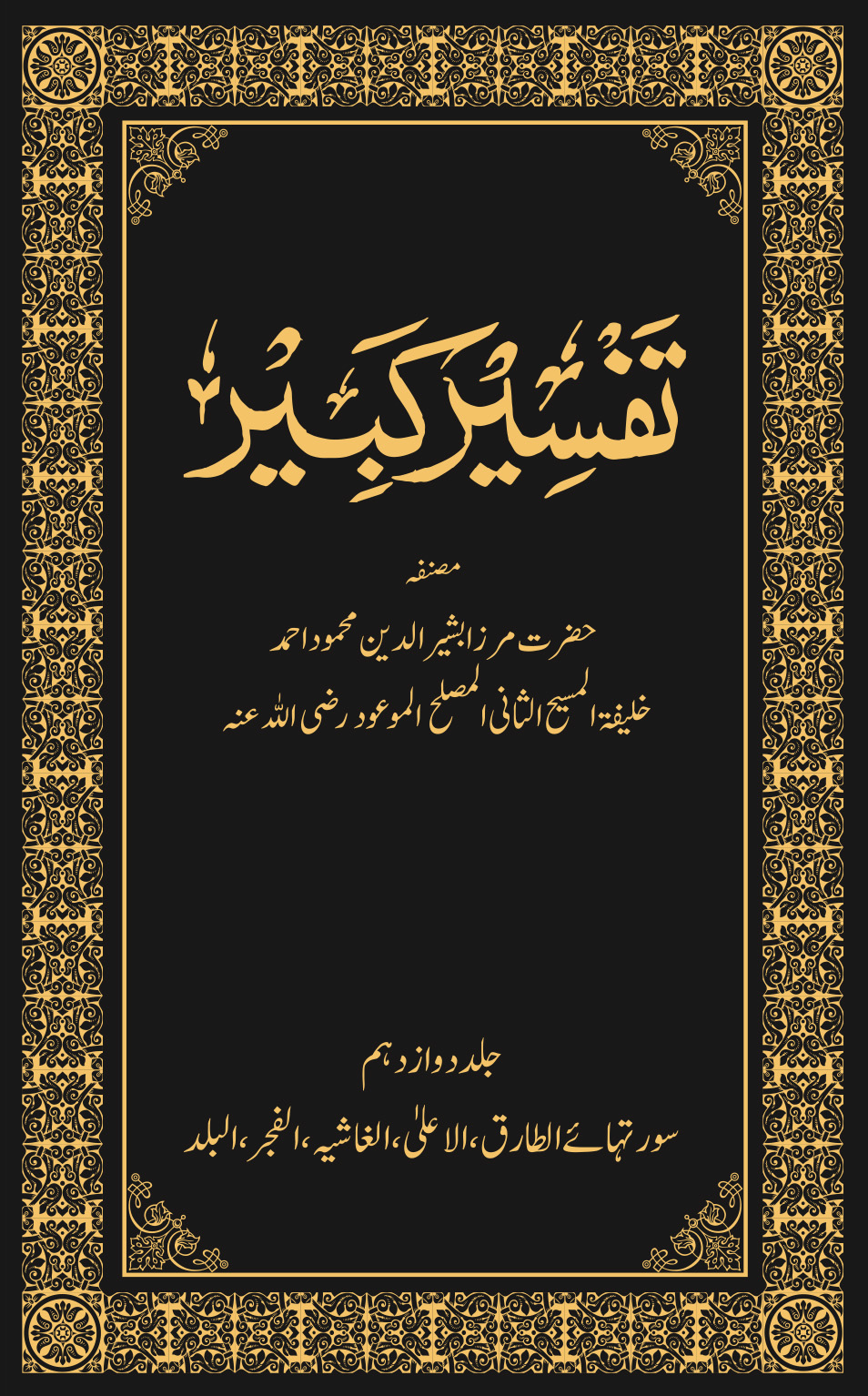Complete Text of Tafseer-e-Kabeer Volume 12
Content sourced fromAlislam.org
Page 5
سُوْرَۃ ُ الطَّارِقِ مَکِّیَّۃٌ سورۃ طارق.یہ سورۃ مکی ہے وَھِیَ دُوْنَ الْبَسْمَلَۃِ سَبْعَ عَشْـرَۃَ اٰیَۃً اور بسم اللہ کے علاوہ اس کی سترہ آیتیں ہیں.نزول کا وقت.سورۂ طارق مکی ہے یہ سورۃ مکی ہے بعض راوی کہتے ہیں کہ جب ایک نجم ثاقب کے گرنے سے ابو جہل ڈر گیا تو اس وقت اس سورۃ کی پہلی تین آیات نازل ہوئیں.نولڈکے اور میور کا خیال ہے کہ یہ سورۃ نہایت ابتدائی سورتوں میں سے ہے مگر پادری ویری لکھتے ہیں کہ چونکہ اس میںکفّار کے نقصان دہ منصوبوں کا بھی ذکر ہے اس لئے ۱۱ سے ۱۷ تک کی آیات ۴بعد زمانہ نبوت کی ہیں.(A Comprehensive Commentary on The Quran by Wherry vol:4 Page:235) میں بار بار لکھ چکا ہوں کہ ایسے استدلال محض دشمنی کی وجہ سے ہیں ورنہ قرآن کریم پیشگوئیوں سے بھرا ہوا ہے کیوں اسے پیشگوئی نہ سمجھا جائے.دوسرے ایسے باریک فرق سے ہمارا کوئی نقصان بھی نہیں.کیونکہ اگر یہ سمجھا جائے کہ دشمنی کے اظہار کے بعد یہ آیت نازل ہوئی ہے تو یہ تو ماننا پڑے گا کہ قرآن کریم نے اس ابتدائی زمانہ میں ہی دشمن کی تباہی کی خبر دے دی تھی.پس اس پیشگوئی کے پورا ہونے کا تو ویریؔ صاحب کو بھی انکار نہیں.سورۂ طارق کا تعلق پہلی سورتوں سے یہ سورۃ اس سلسلہ مضمون کی جو بیان ہوتا آ رہا ہے چوتھی سورۃ ہے اِذَا السَّمَآءُ انْفَطَرَتْ اس سلسلہ کی پہلی سورۃ تھی اِذَا السَّمَآءُ انْشَقَّتْ دوسری سورۃ تھی اور وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الْبُرُوْجِ تیسری سورۃ تھی اور وَالسَّمَآءِ وَالطَّارِقِ یعنی یہ سورۃ جو زیر بحث ہے اس سلسلہ کی چوتھی سورۃ ہے سورۃ تطفیف کے متعلق میں نے بتایا تھا کہ اس میں اس مضمون کے ایک پہلو کو بیان کیا گیا ہے جو اِذَا السَّمَآءُ انْفَطَرَتْ میں بیان کیا گیا تھا.چنانچہ میرے اس دعویٰ کی دلیل یہ ہے کہ سورۃ تطفیف کے بعد دو سورتیں سَـمَاء کے لفظ سے شروع ہوتی ہیں مگر سورۃ تطفیف کے شروع میں وَالسَّمَآءِ نہیں کیونکہ وہ پہلی سورۃ کے سلسلہ میں ہی بیان کی گئی ہے.غرض یہ اس سلسلہ کی آخری سورۃ ہے اس کے بعد وَالسَّمَآءِ کا لفظ نہیں سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى سے نئی سورۃ کا مضمون شروع
Page 6
ہوگا.میرے نزدیک سورہ طارق ایک عالمِ برزخ کے طور پر درمیان میں آئی ہے جس میں پہلے مضمون کو بدل کر ایک دوسری طرف پھیرا جائے گا.اس سورۃاور پچھلی تین سورتوں میں سَـمَاء کے لفظ کو دہرایا گیا ہے لیکن ہر جگہ اس کے ساتھ ایک اور چیز کو بیان کیا گیا ہے پہلے اِذَا السَّمَآءُ انْفَطَرَتْ کہا تھا پھر اِذَا السَّمَآءُ انْشَقَّتْ فرمایا.گویا سَـمَاء کا لفظ تو وہی ہے مگر پہلی دفعہ اس کے ساتھ اِنْفِطَار کا ذکر کیا پھر سَـمَاء کے لفظ کے ساتھ اِنْشِقَاق کا ذکر کیا.پھر تیسری سورۃ میں سَـمَاء کے لفظ کے ساتھ ذَاتِ الْبُـرُوْجِ وَالْیَوْمِ الْمَوْعُوْدِ کا ذکر کیا.اور یہاں سَـمَاء کے ساتھ طارق کا لفظ بڑھایا گیا ہے.دوسرافرق یہ ہے کہ پہلی سورۃ میں سماء کے واقعات کو بیان کیا گیا ہے اور دوسری سورتوں میں سَـمَاء کو بطور شہادت پیش کیا گیا ہے.بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۰۰۱ (میں) اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا (اور) بار بار رحم کرنے والا ہے (پڑھتا ہوں) وَالسَّمَآءِ وَالطَّارِقِ۰۰۲ وَ مَاۤ اَدْرٰىكَ مَا الطَّارِقُۙ۰۰۳ (مجھے) قسم ہے آسمان کی اور صبح کے ستارے کی اور کس چیز نے تجھے علم دیا ہے کہ صبح کا ستارہ کیا ہے.حلّ لُغات.اَلطَّارِقُ.طَارِقٌ کے عربی زبان میں تین معنے ہوتے ہیں (۱) اَلْآتِیْ لَیْلًا یعنی رات کو آنے والا شخص (۲) اَلنَّجْمُ الَّذِیْ یُقَالُ لَہٗ کَوْکَبُ الصُّبْحِ وہ ستارہ جسے کوکب صبح کہتے ہیں اور جو صبح کے طلوع ہونے کی خبر دیتا ہے (۳) اَلضَّارِبُ بِالْـحَصٰی عَلٰی سَبِیْلِ التَّکَھُّنِ علم نجوم رکھنے والا شخص جو کنکریاں پھینک کر نتائج اخذ کرے.(اقرب ) تفسیر.طَارِقٌ کے تین معنی لغت میں ہیں جیسا کہ حل لغات میں بتایا گیا ہے سوال یہ ہے کہ کیا یہ تینوں معنی اس جگہ چسپاں ہوتے ہیں یا ان میں سے کوئی ایک؟ اس بارہ میں یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ ہم بعض جگہ قرآن کریم کے ایک لفظ کے پانچ پانچ چھ چھ معنے کر جاتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں یہ شبہ رہتا ہے کہ شائد زبردستی معنے کر دیئے جاتے ہیں.ہمارے طریق کی اس آیت سے اور ایسے ہی بعض اور آیات سے تصدیق نکلتی ہے جب لغت میں ایک لفظ کے ایک سے زائد معنی ہوں تو
Page 7
بہرحال دو حالتیں ہو ں گی یا یہ کہ عبارت میں ایک معنی مراد لئے گئے ہیں اور یا یہ کہ ایک سے زیادہ معنے مراد لئے گئے ہیں.پھر جہاں ایک سے زیادہ معنے لئے گئے ہوں ان میں سے بھی سارے معنے لئے جا سکیں گے اور کبھی یہ ہو گا کہ بعض لئے جا سکیں گے اور بعض نہیں.پھر جہاں صرف ایک معنی مراد لئے گئے ہوں وہاں بھی دو صورتیں ہوں گی کبھی ایک معنے اتنے واضح ہوں گے کہ عبارت سے صاف ثابت ہو گا کہ یہی معنے اس جگہ چسپاں ہو سکتے ہیں.اور کبھی وہ معنے اتنے واضح نہیں ہوں گے اور اس کے لئے کسی اشارہ کی ضرورت ہو گی.قرآن کریم میں جس جگہ کسی لفظ کے ایک معنے لینے ہوں دوسرے نہ لینے ہوں وہاں مَاۤ اَدْرٰىكَ کا لفظ آتا ہے.گویا ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں مگر مَاۤ اَدْرٰىكَ کے الفاظ کے بعد ایک معنی بتا کر اللہ تعالیٰ یہ بتا دیتا ہے کہ ہم اس جگہ اس سے یہ خاص معنے مراد لیتے ہیں یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ جہاں مَاۤ اَدْرٰىكَ کا لفظ نہیں آتا وہاں ہمارا حق ہے کہ ہم اس کے کئی معنے کریں ورنہ وجہ کیا ہے کہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ معنوں کو محدود کر دیتا ہے اور دوسری جگہ محدود نہیں کرتا اس کی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ ایک لفظ کے کئی کئی معنے کرنا قرآن کریم کے اصول کے خلاف نہیںہاں جس جگہ وہ خود معنوں کو محدود کر دے وہاں ہمارا حق نہیں کہ ہم ان معنوں کو ترک کر کے کوئی اور معنے کریں.پس وہ لوگ جو ہماری تفسیر پر یہ اعتراض کیا کرتے ہیں کہ ہم کیوں ایک لفظ کے کئی کئی معنے جو لغت سے ثابت ہوتے ہیں کرتے ہیں ان کا یہ اعتراض قلتِ تدبّر اور قرآن کریم پر غور نہ کرنے کا نتیجہ ہے.وَ السَّمَآءِ وَ الطَّارِقِ میں مَاۤ اَدْرٰىكَ کہہ کر لفظ طارق کے معنی کی تعیین یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَ مَاۤ اَدْرٰىكَ مَا الطَّارِقُ.النَّجْمُ الثَّاقِبُ.اگر مَاۤ اَدْرٰىكَ کا لفظ یہاں نہ ہوتا تو کوئی کہہ دیتا کہ طارق سے مراد یہاں رات کو آنے والا ہے، کوئی کہہ دیتا کہ یہاں طارق سے کاہن مراد ہے مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے معنے کو محدود کرتے ہوئے فرما دیا وَ مَاۤ اَدْرٰىكَ مَا الطَّارِقُ تمہیں کس نے بتایا کہ طارق کون ہے یعنی تمہارے پاس اس لفظ طارق کا صحیح مفہوم سمجھنے کا کوئی ذریعہ نہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہو سکتا کہ عرب لوگ طارق کے معنے نہیں جانتے تھے یہ عربی کا لفظ ہے اور اہل عرب جانتے تھے کہ طارق کے کیا کیا معنے ہیں.طارق سے مراد صبح کا ستارہ پس مَاۤ اَدْرٰىكَ مَا الطَّارِقُ کا بجز اس کے اور کوئی مطلب نہیں کہ طارق کے کئی معنوں میں سے تم کو کس طرح پتہ لگ سکتا ہے کہ ہم اس جگہ طارق کے کون سے معنے مراد لے رہے ہیں اس لئے ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ النَّجْمُ الثَّاقِبُ ہماری مراد یہاں طارق کے لفظ سے صبح کا ستارہ ہے.سورۂ طارق کا تعلق سورۂ بروج سے اس سورۃ کا پہلی سورۃ سے یہ تعلق ہے کہ پہلی سورۃ میں اور
Page 8
اس سے پہلی سورۃ میں یہ مضمون بیان کیا گیا تھا کہ آنے والا بدر کی صورت میں آئے گا جیسے فرمایا وَالْقَمَرِ اِذَا اتَّسَقَ کہ میں تیرھویں کے چاند کو بطور شہادت پیش کرتا ہوں یا فرمایا تھا وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الْبُرُوْجِ وَالْیَوْمِ الْمَوْعُوْدِ یعنی بارہ بروج کے بعد ایک تیرھویں موعود کی خبر دی گئی تھی.آخری زمانہ میں آنے والے موعود کے دو نام دو مختلف وجوہات سے پس پہلی دونوں سورتوں میں آنے والے کے متعلق یہ بیان کیا گیا تھا کہ وہ بدر ہو گا.بدر کے لفظ سے ایک شبہ پیدا ہوتا تھا اورو ہ یہ کہ گو بدر یہ بتاتا ہے کہ اس نے سورج کی روشنی کو پورے طور پر دوسروں تک پہنچا دیا ہے لیکن بدر ایک اور طرف بھی اشارہ کرتا ہے اور وہ یہ کہ سورج لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو گیا ہے.پس اگر بدر پر ہی خاتمہ ہے تو دوسرے معنی اس کے یہ ہوں گے کہ نورِ محمدؐی براہِ راست اپنا پَرتَو اب دنیا پر نہیں ڈالے گا اور یہ ایک نقص ہے.نورِ محمدؐی اگر براہِ راست اپنا پَرتَو نہیں ڈالے گا تو اس کے معنے درحقیقت یہ بن جاتے ہیں کہ ہم نورِ محمدؐی کو تو دیکھیں گے مگر بواسطہ ایک دوسرے وجود کے.اسے الگ نہیں دیکھیں گے.حالانکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے اصل نبی ہیں اور جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہو کر آتا ہے وہ آپؐکا تابع ہوتا ہے اور کوئی تابع اپنے متبوع کے رستہ میں روک بن کر کھڑ انہیں ہو سکتا اگر کوئی ایسا شخص آئے تو وہ خاتمِ سلسلہ ہی ہو سکتا ہے جیسے حضرت عیسٰی علیہ السلام آئے انہوں نے نورِ موسوی کو روکا مگر ساتھ ہی اسے ختم کر دیا.لیکن یہاں اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ ہم جو ایک موعود کی خبر دے رہے ہیں وہ پہلے لوگوں کی طرح نہیں ہو گا وہ آخری ہوتے تھے ان معنوں میں کہ سلسلہ ان پر ختم ہو جاتا تھا مگر اسلام میں آنے والا دو نام رکھتا ہے ایک بدر اور ایک طارق.بدر اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ سورج غروب ہو گیا اب اس کی روشنی بدر کے ذریعہ ہی دنیا تک پہنچ سکتی ہے اس کے بغیر نہیں.لیکن طارق اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ سورج چڑھنے والا ہے پس یہ نہیں ہو گا کہ آنے والا نورِ محمدؐی کو روک دے گا بلکہ وہ ایک لحاظ سے بدر ہو گا اور ایک لحاظ سے طارق ہو گا.وہ بدر ہو گا اس لحاظ سے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نورِ نبوت اپنے اندر جذب کر کے دنیا تک پہنچائے گا اور وہ طارق ہو گا ان لوگوں کے لحاظ سے جو اس سے تعلق پیدا کریں گے.کیونکہ وہ اس سے تعلق پیدا کرنے کے بعد براہِ راست رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق پیدا کر لیں گے.گویا بدر کے لحاظ سے وہ نورِ نبوت کو لے کر لوگوں تک پہنچائے گا اور طارق کے لحاظ سے لوگوں میں یہ استعداد پیدا کرے گا کہ براہِ راست نورِ محمدؐی کا اکتساب کریں.پس بدر اور طارق دو نام ہیں جو آنے والے موعود کے رکھے گئے ہیں اور عجیب بات یہ ہے کہ حدیثوں میں بھی آنے والے کے دو نام رکھے گئے ہیں ایک مسیح اور ایک مہدی.(سنن ابن ماجہ، ابواب الفتن، باب شدّۃ الزمان)
Page 9
اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے لکھا ہے کہ میرا مدار مہدی کے نام پر ہے گو ہماری جماعت میں مسیح موعود نام زیادہ مشہور ہے درحقیقت بدر قائم مقام ہے عیسیٰ کا اور طارق قائم مقام ہے مہدی کا.عیسوی مقام پر کھڑے ہونے والے جس قدر لوگ آئے ہیں وہ صرف آخری ہی نہیں تھے بلکہ مسبوق شرعی نبی کے خاتِم بھی تھے.ان کے آنے پر وہ سلسلہ ختم ہو گیا اور ایک نیا سلسلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جاری کیا گیا.اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آنے والے کا نام مسیح بھی رکھا اور مہدی بھی رکھا.نبی بھی رکھا اور امّتی بھی رکھا.نبی کے لحاظ سے وہ بدر ہے اور امّتی کے لحاظ سے وہ طارق ہے پس قرآن کریم نے آنے والے کے دو نام رکھے ہیں ایک اِتِّسَاقِ قَـمْر یا یَوْمِ مَوْعُوْد اور ایک طَارِق جس میں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ وہ پھر نورِ محمدؐی کو دنیا میں روشن کر دے گا گویا وہ اسلام کی ترقی اور انوارِ محمدؐی کے ظہور کی خبر دینے والا ہوگا.اس طرح ان سورتوں میں دونوں پیشگوئیوں کو بیان کر دیا گیا ہے عیسٰی کی پیشگوئی پہلی دو جگہ بیان ہوئی ہے اور مہدویت کی پیشگوئی اس جگہ بیان ہوئی ہے.یہ بات بھی اپنے اندر ایک لطافت رکھتی ہے کہ اس سورۃ کے آخر میں پھر مضمون کو پہلے زمانہ کی طرف پھیر دیا گیا ہے جیسے فرماتا ہے فَمَهِّلِ الْكٰفِرِيْنَ اَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا.گویا آخر میں پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم کی طرف مضمون کو پھیر دیا اور جس طرح مضمون کا ابتداء رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم کے ذکر سے کیا گیا تھا اسی طرح مضمون کا خاتمہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم کے ذکر پر کیا گیا ہے.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم شہادت کے طور پر پیش کرتے ہیں آسمان کو.پہلی سورۃ میں بھی آسمان کو بطور شہادت پیش کیا گیا تھا مگر وہاں فرمایا تھا وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الْبُرُوْجِ وہاں اس ترتیب کو بیان کیا گیا تھا کہ مختلف حالتوں میں سے اسلام گذرتا جائے گا.اور ہر زمانہ میںاللہ تعالیٰ کی طرف سے تجدید دین کا کام جاری رہے گا یہاں تک کہ یَوْمِ مَوْعُوْد آ جائے گا یعنی ایسا شخص کھڑا ہو گا جس کا نام نبی ہو گا اور لوگوں کے دلوں میںشبہ پیدا ہو گا کہ شائد نورِ محمدؐی ختم ہوگیا ہے.چونکہ یہ شبہ لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو سکتا تھا اس لئے فرماتا ہے اب ہم اس کی دوسری جہت کو پیش کرتے ہیں کہ اس کی ایک جہت ایسی ہی ہے جیسے طارق ہوتا ہے.جس طرح آسمانی نظام میں دونوں باتیں ہوتی ہیں چاند بھی ہوتا ہے اور تاریک راتیں بھی ہوتی ہیں.اسی طرح وہ بدر بھی ہو گا اور طارق بھی.گویا ایک نام ایک جہت سے ختم کرنے کے معنی دیتا ہے اور دوسرا نام دوسرے جہت سے اجراء کے معنے دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ مسیح موعودؑ کی بعثت جہاں نورِ محمدؐی کو بالواسطہ پھیلائے گی.وہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو بھی دنیا میں قائم کردے گی.پس آپؐکا بدر نام ہے اس وقت کا جب تک کہ اسلام کو غلبہ حاصل نہیں ہوتا اور صرف روحانی فیوض
Page 10
ظاہر کئے جاتے ہیں جن میں مسیح موعود کا وجود بطور واسطہ اور آئینہ کے ہے اور طارق نام ہے اس وقت کا جب اسلام کو غلبہ حاصل ہو جائے گا کیونکہ مہدی کے ہاتھ پر ہی اسلام کی فتح اور اس کا غلبہ اور اس کی شریعت کا قیام مقدر ہے.جب تک اسلام کے غلبہ کا زمانہ آئے مسیح موعودؑ کا بدر نام غالب رہے گا.بدر کی جنگ میں بھی مسلمان سخت کمزور تھے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بدری زمانہ فتح کی علامت ہے لیکن ساتھ ہی وہ کمزوری کی بھی علامت ہے مگر نَـجْمُ الثَّاقِب کمزوری کو اپنے پیچھے چھوڑتا ہوا ترقی کو اپنے آگے لے آتا ہے.دونوں جگہ سَـمَاء کا لفظ رکھ کر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا ہے کہ یہ دونوں نظام آسمان کے تابع ہیں یعنی الہام الٰہی سے وابستہ ہوں گے.بدری مقام بھی الہام الٰہی سے وابستہ ہو گا اور مہدویت کا مقام بھی الہام الٰہی سے وابستہ ہوگا.بغیر آسمانی نظام کے نہ بدری مقام حاصل ہو سکتا ہے اور نہ طارق کا مقام حاصل ہو سکتا ہے یہ دونوں عہدے آسمانی نظام چاہتے ہیں.اور پھر اس آسمانی نظام کو دہرانے میں ایک یہ بھی غرض ہے کہ مسیح موعودؑ کی بعثت کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اس کے مختلف مظاہر پیدا کرتا رہے گا کوئی مہدویت کا مظہر ہو گا اور کوئی مسیحیت کا مظہر ہو گا مگر ان پر الہام الٰہی کا ہونا ضروری ہوگا کیونکہ دونوں جگہ سَـمَاء کا لفظ رکھا گیا ہے جو الہام الٰہی کی طرف اشارہ کرتا ہے.النَّجْمُ الثَّاقِبُۙ۰۰۴ وہ ستارہ (وہ ہے) جو بہت چمکتا ہے.حلّ لُغات.الثَّاقِبُ.الثَّاقِبُ: ثَقَبَ سے اسم فاعل ہے اور ثَقَبَ کے معنے چھید کرنے کے ہوتے ہیں.(اقرب) اور اَلنَّجْمُ الثَّاقِبُ کے معنے ہیں.روشن ستارہ جو ظلمت کو چھید دے.نیز کہتے ہیں ثَقَبَ النَّجْمُ اور معنے ہوتے ہیں اَضَاءَ یعنی ستارہ روشن ہوا(منجد).زمخشری اپنی کتاب اساس میں لکھتے ہیں کہ کَوْکَبٌ ثَاقِبٌ وَّ دُرِّیٌّ کے معنے ہیں شَدِیْدُ الْاِضَاءَۃِ وَالتَّلَالُـؤِ کَاَنَّہٗ یَثْقُبُ الظُّلْمَۃَ فَیَنْفُذُ فِیْـھَا وَیَدْرَاُھَا اَیْ یَدْفَعُھَا (اقرب) یعنی کَوْکَبٌ ثَاقِبٌ یا کَوْکَبٌ دُرِّیٌّ کے معنے ہوتے ہیں ایک چمکتا ہوا ستارہ جس میں خوب روشنی اور چمک ہو گویا وہ ظلمت کو چھید دیتا اور اس میں گھس کر ہر قسم کی تاریکی کو دور کر دیتا ہے.اَلنَّجْمُ.اَلنَّجْمُ (۱)اَلْکَوْکَبُ ستارا (۲)اَلنَّبَاتُ عَلٰی غَیْـرِ سَاقٍ وَ ھُوَ خِلَافُ الشَّجَرِ کے بے جڑ والی بوٹی جس کو ہمارے ملک میں بیل کہتے ہیں.(۳) اَلْاَصْلُ کسی چیز کی جڑ.کہتے ہیں.ھُوَ مِنْ نَـجْمِ صِدقٍ وہ
Page 11
سچائی کی جڑ سے ہے اَلنَّجْمُ لَیْسَ لِھٰذَا الْـحَدِیْثِ نَـجْمٌ اَیْ اَصْلٌ نَـجْمٌ کی جمع اَنْـجُمٌ وَ اَنْـجَامٌ وَ نُـجُوْمٌ وَنُـجُمٌ آتی ہے.(اقرب) یعنی اس کی بات سچی ہوتی ہے یا وہ اعلیٰ خاندان سے ہے.تفسیر.جیسا کہ اوپر بتایا جا چکا ہے.بدر کے لفظ سے یہ بتایا گیا تھا کہ بدری لحاظ سے باوجود ظلمتِ زمانہ کے آنے والا موعود نورِ محمدی کو پھیلا دے گا.اور اس کی جماعت اسلام کی خادم ہو گی اور طارق کے لحاظ سے یہ بتایا گیا ہے کہ وہ ہر قسم کی ظلمتوں کو پھاڑ دے گا.درحقیقت محمدی زمانہ جلال کا زمانہ ہے اور فتوحات مہدویت سے تعلق رکھتی ہیں اس لئے طارق کا لفظ لا کر بتا دیا کہ اس کے آنے کے ساتھ اسلامی فتوحات کا زمانہ آجائے گا اور تمام قسم کی ظلمات کو وہ پھاڑ کر رکھ دے گا.اِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌؕ۰۰۵ (اس امر پر قسم کھاتے ہیں کہ اس قسم کی) کوئی جان نہیں جس پر ایک نگران (خدا تعالیٰ کی طرف سے ) مقرر نہ ہو.حلّ لُغات.لَمَّا.لَمَّا کے کئی معنے ہوتے ہیں جن میں سے ایک اِلَّا کے ہیں چنانچہ لغت میں لکھا ہے وَالثَّالِثُ مِنْ اَوْجَھِھَا اَنْ تَکُوْنَ حَرْفُ اسْتِثْنَاءٍ فَتَدْخُلُ عَلَی الْـجُمْلَۃِ الْاِسْـمِیَّۃِ نَـحْوُ اِنْ کُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَیْـھَا حَافِظٌ (اقرب) یعنی لَمَّا کی تیسری قسم یہ ہے (ہر قسم کی بھی آگے کئی کئی اقسام ہیں) کہ یہ حرفِ استثناء ہوتا ہے اور جملہ اسمیہ پر آتا ہے جیسے قرآن کریم کی یہ آیت ہے کہ اِنْ کُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَیْھَا حَافِظٌ.یہاں سیبویہ کا ایک فقرہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اَعْـجَبُ الْکَلِمَاتِ کَلِمَۃُ لَمَّا اِنْ دَخَلَ عَلَی الْمَاضِی یَکُوْنُ ظَرْفًا وَ اِنْ دَخَلَ عَلَی الْمُضَارِعِ یَکُوْنُ حَرْفًا وَ اِنْ دَخَلَ لَا عَلَی الْمَاضِی وَلَا عَلَی الْمُضَارِعِ یَکُوْنُ بِـمَعْنٰی اِلَّا (اقرب) یعنی لَمَّا ایک عجیب کلمہ ہے اگر ماضی پر داخل ہو تو ظرف کے معنے دیتا ہے اور اگر مضارع پر داخل ہو تو حرف ہوتا ہے اور اگر نہ ماضی پر داخل ہو اور نہ مضارع پر تو اس کے معنے اِلَّا کے ہوتے ہیں.بہرحال لَمَّا کے کئی معنے ہوتے ہیں اور جب یہ جملہ اسمیہ پر آتا ہے تو اس کے معنے اِلَّا کے ہوتے ہیں لیکن درحقیقت عربی محاورہ سے پتہ لگتا ہے کہ جب یہ اسم پر آئے اس وقت ہی اس کے معنے اِلَّا کے نہیں ہوتے بلکہ اسم کے بغیر بھی یہ اِلَّا کے معنے دیتا ہے چنانچہ کہتے ہیں اَنْشُدُکَ اللّٰہَ لَمَّا فَعَلْتَ.اَیْ مَااَسْاَلُکَ اِلَّا فِعْلَکَ یعنی سوائے تمہارے کام کے مجھے کسی اور سے غرض نہیں(اقرب).تفسیر.فرماتا ہے اِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ہر جان جو دنیا میں آتی ہے اس پر ایک نگران مقرر
Page 12
ہوتا ہے.اس آیت کے لوگوں نے مختلف معنی کئے ہیں جن میں سے ایک یہ ہیں کہ ہر انسان کا خدا حافظ ہے.چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ایک دوسرے مقام پر فرماتا ہےوَ كَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيْبًا (الاحزاب:۵۳) اللہ تعالیٰ ہر چیز پر رقیب ہے.اور نفس شے کے تابع ہے جب ہر چیز پر وہ رقیب ہے تو نفس بھی اسی میں آ گیا اسی طرح فرماتا ہے اِنَّ عَلَیْکُمْ لَحٰفِظِیْنَ.کِرَامًا کَاتِبِیْنَ (الانفطار:۱۱،۱۲) کہ یقیناً تم پر تمہارے خدا کی طرف سے نگران مقرر ہیں فرماتا ہے لَهٗ مُعَقِّبٰتٌ مِّنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهٖ يَحْفَظُوْنَهٗ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ(الرّعد:۱۲) یعنی اللہ کی طرف سے اس کے آگے بھی اور اس کے پیچھے بھی ایک دوسرے کے پیچھے آنے والی ایک ملائکہ کی جماعت حفاظت کے لئے مقرر ہے جو اس کی اللہ کے حکم سے حفاظت کر رہے ہیں.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایک روایت مروی ہے آپؐفرماتے ہیں وُکِّلَ بِالْمُؤْمِنِ مِائَۃٌ وَّسِتُّوْنَ مَلَکًا یَذُبُّوْنَ عَنْہُ کَمَا یُذَبُّ عَنْ قَصْعَۃِ الْعَسَلِ الذُّبَابُ (روح المعانی زیر آیت اِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ) یعنی ہر مومن پر ایک سو ساٹھ فرشتے مقرر ہوتے ہیں اور وہ اس سے اسی طرح شیطانی تحریکیں دور کرتے رہتے ہیں جس طرح شہد کے پیالہ سے مکھیاں اڑائی جاتی ہیں.غرض انسان کی حفاظت کا قرآن اور حدیثوں دونوں سے پتہ لگتا ہے اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ انسان کا نگران ہوتا ہے اور ملائکہ بھی اس فرض کو ادا کرتے ہیں.مگر میرے نزدیک اِنْ کُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَیْھَا حَافِظٌ میں کُلُّ سے مراد صرف اس قسم کے لوگ ہیں جو نَـجْمُ الثَّاقِب یا اس کے قائم مقام ہوں اور چونکہ اس قسم کے کئی لوگ ہوئے ہیں.حضرت موسٰی بھی اس میں شامل تھے.حضرت عیسٰیؑ بھی اس میں شامل تھے.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں شامل تھے.حضرت مسیح موعود علیہ السلام بھی اس میں شامل تھے.غرض ایک جماعت اس سے مراد تھی اس لئے کُلُّ کا لفظ استعمال فرمایا.گویا کُلُّ نَفْسٍ سے مراد کُلُّ نَفْسٍ مِنْ ھٰذَا الْقِسْمِ ہے کہ اس قسم سے تعلق رکھنے والی ہر جان پر ایک نگران مقرر ہے اور وہ نگران خدا تعالیٰ کی ذات ہے جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وَاللّٰہُ یَعْصِمُکَ مِنَ النَّاسِ (المائدۃ:۶۸) کہ اللہ تمہیں لوگوں کے منصوبوں سے بچائے گا.یہی الہام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ہوا (انجام آتھم روحانی خزائن جلد ۱۱ صفحہ ۶۰) اور اسی قسم کا الہام حضرت مسیح ناصریؑ کو بھی ہوا کہ يٰعِيْسٰۤى اِنِّيْ مُتَوَفِّيْكَ وَ رَافِعُكَ اِلَيَّ وَ مُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَ جَاعِلُ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْكَ فَوْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْۤا اِلٰى يَوْمِ
Page 13
الْقِيٰمَةِ(اٰل عـمران:۵۶) یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے عیسٰی میں تجھے طبعی طور پر وفات دوں گا اور تجھے اپنے حضور عزت بخشوں گا.اور کافروں کے الزامات سے تجھے پاک کروں گا اور جو تیرے پیرو ہیں انہیں ان لوگوں پر جو منکر ہیں قیامت کے دن تک غالب رکھوں گا.سلسلہ کا پہلا اور آخری نبی قتل نہیں ہوتا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بھی تحریر فرمایا ہے کہ سلسلہ کا پہلا اور آخری نبی کبھی قتل نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ اس کی خود حفاظت کیا کرتا ہے چنانچہ حضور فرماتے ہیں:.’’اگرچہ قتل ہونا مومن کے لئے شہادت ہے لیکن عادت اللہ اسی طرح ہے کہ دو قسم کے مرسل من اللہ قتل نہیں ہوا کرتے.(۱) ایک وہ نبی جو سلسلہ کے اوّل پر آتے ہیں جیسا کہ سلسلہ موسویہ میں حضرت موسٰی اور سلسلہ محمدؐیہ میں ہمارے سیّد ومولیٰ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم (۲) دوسرے وہ نبی اور مامور من اللہ جو سلسلہ کے آخر میں آتے ہیں جیسے کہ سلسلہ موسویہ میں حضرت عیسٰی علیہ السلام اور سلسلہ محمدؐیہ میں یہ عاجز‘‘ (تذکرۃ الشہادتین روحانی خزائن جلد ۲۰ صفحہ ۶۹،۷۰) پس اِنْ کُلُّ نَفْسٍ سے مراد اِنْ کُلُّ نَفْسٍ مِنْ ھٰذِہِ الطَّائِفَۃِ ہے اگر ہم نفس سے مراد عام نفس لے لیں تو گو سارے نفسوں کی حفاظت کا قرآن کریم سے بھی پتہ لگتا ہے اور حدیثوں سے بھی پتہ لگتا ہے مگر مجھے ان معنوں کا اَلنَّجْمُ الثَّاقِبُ سے کوئی جوڑ نظر نہیں آتا لیکن جو معنے میں کرتا ہوں ان سے آیات کا جوڑ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ اس قسم کے لوگ جو اَلنَّجْمُ الثَّاقِبُ ہوں اللہ تعالیٰ ان کی خود حفاظت کرتا اور انہیں دشمنوں کی شرارتوں اور منصوبوں سے محفوظ رکھتا ہے ثاقب اسی لئے فرمایا کہ وہ دوسروں کو مارے گا.اس کو کوئی نہیں مار سکتا.فرماتا ہے یہ وہ ستارہ ہے جو دوسروں کو چھید ڈالے گا مگر اس قسم کے آدمیوں کو اور کوئی چھید نہیں سکتا.فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَؕ۰۰۶ پس انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے.خُلِقَ مِنْ مَّآءٍ دَافِقٍۙ۰۰۷ وہ ایک اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا ہے.
Page 14
يَّخْرُجُ مِنْۢ بَيْنِ الصُّلْبِ وَ التَّرَآىِٕبِؕ۰۰۸ وہ (پانی یا انسان) پیٹھ اور سینہ کی ہڈیوں سے نکلتا ہے.حلّ لُغات.دَافِقٌ.دَافِقٌ دَفَقَ سے ہے اور دَفَقَ الْمَاءُ کے معنے ہوتے ہیں اِنْصَبَّ بِـمَرَّۃٍ دفعۃً پانی بہہ پڑا (اقرب) اَلدَّافِقُ کے معنے ہیں اَلْمُنْصَبُّ دفعۃً بہنے والا.(اقرب) اَلصُّلْبُ.اَلصُّلْبُ وَالصَّالِبُ.عَظْمٌ فِی الظَّھْرِ ذُوْفَقَارٍ مِنْ لَّدُنِ الْکَاھِلِ اِلَی الْعَجْبِ (اقرب) صلب اور صالب دونوں ریڑھ کی ہڈی کو کہتے ہیں یعنی کندھوں سے لے کر عـجب الذنب تک جو ہڈی ہے اسے صلب بھی کہتے ہیں اور صالب بھی کہتے ہیں.تَرَائِب.تَرَائِب تَرِیْبَۃٌ کی جمع ہے.اور اس کے معنے سینہ کی ہڈیوں کے ہیں (اقرب) پس لفظی معنی يَخْرُجُ مِنْۢ بَيْنِ الصُّلْبِ وَ التَّرَآىِٕبِکے یہ ہوئے کہ وہ پانی جو نکلتا ہے پیٹھ اور سینہ کی ہڈیوں کے درمیان سے.تفسیر.يَخْرُجُ مِنْۢ بَيْنِ الصُّلْبِ وَ التَّرَآىِٕبِ کے ایک لطیف معنے پرانے زمانہ میں لوگوں سے یہ غلطی ہوئی کہ وہ اس آیت کو دیکھ کر اس طرف مائل ہو گئے کہ مادۂ منویہ سینہ اور پیٹھ کی ہڈیوں کے درمیان سے آتا ہے.لیکن حضرت خلیفۂ اوّل رضی اللہ عنہ اس کے ایک بہت ہی لطیف معنی کیا کرتے تھے آپ فرماتے تھے قرآن کریم بڑا لطیف کلام ہے وہ کبھی ننگے الفاظ استعمال نہیں کرتا.اس نے صلب اور ترائب کا ذکر کرکے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ صلب اور ترائب کا جو وسط ہے وہاں سے مَآءٍ دَافِقٍ نکلتا ہے.یہ معنے بڑے لطیف اور قرآن کریم کی شان کے بالکل مطابق ہیں.بَيْنِ الصُّلْبِ وَ التَّرَآىِٕبِ سے مراد مرد کا صلب اور ماں کی چھاتیاں بعض لوگوں نے بَيْنِ الصُّلْبِ سے مراد مرد کا صلب اور ترائب سے مراد عورت کا سینہ لیا ہے (تفسیر ابن کثیر زیر آیت يَخْرُجُ مِنْۢ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَآىِٕبِ) اور وہ معنے یہ کرتے ہیں کہ انسان مرد کی پیٹھ سے پیدا ہوتا اور ماں کی چھاتیوں سے پلتا ہے.گویا صلب سے مراد صُلْبُ الْأَبِ اور ترائب سے مراد تَرَائِبُ الْاُمِّ ہے یہ معنے عام معنوں سے زیادہ معقول ہو جاتے ہیں اور طبی لحاظ سے بھی اس پر کوئی اعتراض واقعہ نہیں ہوتا.
Page 15
اِنَّهٗ عَلٰى رَجْعِهٖ لَقَادِرٌؕ۰۰۹ وہ (خدا تعالیٰ) اس کے دوبارہ لوٹانے پر بھی یقیناً قادر ہے.تفسیر.انسان کے مَآءٍ دَافِقٍ سے پیدا ہونے سے مراد یہاں انسان کی پیدائش کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے اور پہلی بات یہ بتائی ہے کہ خُلِقَ مِنْ مَّآءٍ دَافِقٍ.انسان میں خدا تعالیٰ نے دفق کی قابلیت رکھی ہے کیونکہ اس کی پیدا ئش ہی ایسے پانی سے ہوئی ہے جو اچھلنے والا ہے.چنانچہ انسان کے تمام اعمال بھی اسی اچھلنے کی صفت کے مطابق ہوتے ہیں یعنی وہ ہمیشہ اچھلتا کودتا ہے اور آگے کی طرف بڑھنے کی اس میں رغبت پائی جاتی ہے اور جس طرح اچھلنے والا کبھی اوپر اچھلتا ہے اور کبھی نیچے آتا ہے اسی طرح وہ مختلف دوروں سے گذرتا ہے کبھی وہ ادنیٰ دَور میں سے گذر رہا ہوتا ہے اور کبھی اعلیٰ دَور میں سے.یہ تمام باتیں دلالت کرتی ہیں کہ انسانی فطرت میں بڑھنے کا مادہ رکھا گیا ہے اور ترقی کا راستہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے کھولا ہوا ہے لیکن جب وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا تو نقصان بھی اٹھا لیتا ہے.يَوْمَ تُبْلَى السَّرَآىِٕرُۙ۰۰۱۰ اس دن (لوٹانے پر) جب پوشیدہ بھید ظاہر کئے جائیں گے.فَمَا لَهٗ مِنْ قُوَّةٍ وَّ لَا نَاصِرٍؕ۰۰۱۱ جس کے نتیجہ میں نہ تو (اپنے پر سے مصیبت ٹلانے کی) کوئی طاقت اس کے پاس رہے گی اور نہ اس کا کوئی مددگار ہو گا.حلّ لُغات.تُبْلٰى.تُبْلٰی کے معنے ہیں تُکْشَفُ وَتُعْرَفُ و تُظْھَرُ یعنی ظاہر کئے جائیں گے اور سَـرَائِرُ سَـرِیْرَۃٌ کی جمع ہے اور سَـرِیْرَۃٌ کے معنے ہیں اَلسِّـرُّ الَّذِیْ یُکْتَمُ ایسا راز جس کو انسان چھپاتا ہے اور سَـرِیْرَۃُ الْاِنْسَانِ کے معنی ہیں مَااَسَـرَّہُ مِنْ اَمْرِہٖ خَیْـرًا وَقِیْلَ شَـرًّا یعنی ہر وہ بات جو انسان چھپانا چاہتا ہو.خواہ وہ اچھی ہو یا بری.اسی طرح کہتے ہیں فُلَانٌ طَیِّبُ السَّـرِیْرَۃِ اَیْ سَلِیْمُ الْقَلْبِ صَافِی النِّیَّۃِ یعنی فلاں صاف دل اور صاف نیت ہے (اقرب )
Page 16
تفسیر.السَّرَآىِٕرُ سے مراد چھپی ہوئی باتیں فرماتا ہے یَوْمَ تُبْلَى السَّرَآىِٕرُ جس دن کہ چھپی ہوئی باتیں خدا تعالیٰ ظاہر کر دے گا یا ان کے مطابق انسان کا امتحان لیا جائے گا.ان معنوں کے رو سے مومن و کافر دونوں مراد ہوں گے اور اگر اس کے معنے صافی القلب کے لئے جائیں.تب صرف مومن کے لئے یہ آیت سمجھی جائے گی اور اگر سرائر کے معنے صرف یہ کئے جائیںکہ وہ راز جن کو انسان چھپانا چاہتا ہے تو اس صورت میں یہ آیت صرف کافروں کے لئے ہو گی.فَمَا لَهٗ مِنْ قُوَّةٍ وَّ لَا نَاصِرٍ یہ آیت اس بات کا ثبوت ہے کہ سَـرِیْرَہ کے معنے متذکرہ بالا آیت میں صافی القلب کے نہیں بلکہ اس سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کو انسان چھپاتا ہے اور چھپاتا ہمیشہ بُری باتوں کو ہی ہے فرماتا ہے يَوْمَ تُبْلَى السَّرَآىِٕرُ جس دن کہ انسان کے خراب اور گندے ارادے ظاہر کر دیئے جائیں گے یا اس کا امتحان لیا جائے گا.ایسے انسان کے اندر نہ تو ذاتی طور پر کوئی قوت ہو گی اور نہ اس کا کوئی اور مددگار ہو گا.پہلی آیات میں اَلنَّجْمُ الثَّاقِبُ کا ذکر کیا گیا ہے اور ثقب ہمیشہ ایسی چیز پر ہوا کرتا ہے جو تباہی و بربادی کے قابل ہو.اچھی چیز کو پتھر مار مار کر چھیدا نہیں جاتا پھر اِنْ کُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَیْھَا حَافِظٌ میں یہ بتایا گیا تھا کہ لوگ اس نجم ثاقب کی مخالفت کریں گے مگر اللہ تعالیٰ اس نجم ثاقب کے ذریعہ تاریکی اور ظلمت کو دور کر دے گا اور وہ لوگ جو اس کے وجود کے خلاف منصوبے کریں گے اور خفیہ تدابیر کے ذریعہ اس کے کام کو تباہ کرنا چاہیں گے اللہ تعالیٰ ان کے تمام گند اور بد ارادوں کو ظاہر کر دے گا اور ان کو اس طرح تباہ کرے گا کہ نہ ذاتی طور پر وہ اس تباہی کو روکنے کی طاقت رکھیں گے اور نہ باہر سے کوئی اور شخص ان کی مدد کے لئے کھڑا ہو سکے گا.ایک صاحب نے ایک دفعہ مجھے سنایا کہ میرے والد مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی کے بہت دوست ہوا کرتے تھے اور ان کی مجھے ہدایت تھی کہ مولوی محمد حسین صاحب جب شملہ میں آیا کریں تو میں ان سے ضرور ملنے کے لئے جایا کروں.ایک دفعہ مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی شملہ میں آئے.میں ان کو دبا رہا تھا کہ اتنے میں حافظ عبدالرحمٰن صاحب کتاب الصرف کے مصنّف وہاں آ گئے اور مولوی محمد حسین صاحب سے کہنے لگے کہ مولوی صاحب مرزا قادیانی نے بڑی ترقی کر لی ہے لوگ اس کے معتقد ہوتے جاتے ہیں اور یہ فتنہ روز بروز ترقی کر رہا ہے مختلف گفتگوؤں کے بعد کسی نے کہا کہ ایسے شخص کو کوئی مار بھی نہیں ڈالتا اس پر مولوی محمد حسین صاحب کہنے لگے مشکل یہ ہے کہ کئی دفعہ ایسا بھی لوگوں نے کرنا چاہا ہے مگر وہ کسی نہ کسی طرح بچ جاتا ہے.اسی دوست نے ذکر کیاکہ جب وہ یہ باتیں آپس میں کر رہے تھے تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ مولوی آدمی ہیں.انہیں ان باتوں کا
Page 17
کیا علم.میں خود یہ ثواب حاصل کروں گا اور ان کو ضرور قتل کر کے رہوں گا.یہ ارادہ میں نے پختہ طور پر کر لیا.مگر جب دوسرا دن ہوا تو حافظ عبدالرحمٰن صاحب پھر مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی سے ملنے کے لئے آئے اور کہنے لگے مولوی صاحب اب مرزا صاحب کے مقابلہ کا راستہ نکل آیا ہے مرزا صاحب نے ایک اشتہار شائع کیا ہے جس میں لکھا ہے کہ خدا کے حکم کے ماتحت میں آئندہ کوئی مباحثہ نہیں کروں گا.یہ اشتہار ایسا ہے جس سے مرزا بالکل پکڑا جائے گا.ہم اس کے مقابلہ میں ایک مباحثہ کا اشتہار شائع کر دیتے ہیں اگر اس نے مباحثہ کو مان لیا تو ہم کہیں گے دیکھو ایک طرف تو کہا جاتا ہے کہ خدا نے مجھے مباحثات سے روکا ہے اور دوسری طرف مباحثہ کو منظور کر لیا گیا ہے معلوم ہوتا ہے کہ جو کچھ کہا گیا تھا وہ بالکل جھوٹ تھا اور اگر وہ مباحثہ کے لئے نہیں نکلے گا تب بھی اس کی شکست ہو گی کیونکہ ہم دنیا میں اعلان کر دیں گے کہ ہم مرزا صاحب کو مباحثہ کے لئے بلاتے ہیں مگر وہ میدان میں نکلنے کے لئے تیار نہیں.ان کی یہ بات سنتے ہی مولوی محمد حسین صاحب اٹھ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے حافظ صاحب آپ نے خوب بات نکالی.یہ مرزا قادیانی کو لوگوں کی نگاہ سے گرانے کا نہایت کامیاب حربہ ہے.راوی نے بیان کیا کہ جب ان کی یہ باتیں میں نے سنیں تو اسی وقت یقین کر لیا کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں پہلے دن تو یہاں تک کہتے تھے کہ قتل کرنے والے قتل کرنا چاہتے تھے مگر کامیاب نہیں ہوئے.اور آج ایک خلاف تقویٰ تجویز پر متفق ہو رہے ہیں.ان لوگوں میں ایمان اور تقویٰ بالکل نہیں ہے.چنانچہ یہی واقعہ آخر میں ان کی ہدایت اور قبول احمدیت کا باعث ہو گیا.تو فرماتا ہے يَوْمَ تُبْلَى السَّرَآىِٕرُ فَمَالَهٗ مِنْ قُوَّةٍ وَّ لَا نَاصِرٍ وہ اس نجم الثاقب کو مٹانے کے لئے قسم قسم کی کوششیں کریں گے مگر نہ انہیں ذاتی قوت ملے گی اور نہ کوئی مددگار ملے گا.جو لوگ بھی ان کی مدد کے لئے کھڑے ہوں گے وہ بالکل نکمّے اوربے کار ہوں گے.وَ السَّمَآءِ ذَاتِ الرَّجْعِۙ۰۰۱۲ (اور مجھے) قسم ہے اس بادل کی جو بار بار برسنے والے مینہ پر مشتمل ہوتا ہے.وَ الْاَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِۙ۰۰۱۳ اور اس زمین کی بھی (مجھے قسم ہے) جو (بارش کے جواب میں) روئیدگی والی (ہو جاتی)ہے.حلّ لُغات.السَّمَآءُ.السَّمَآءُ کے لغت میں کئی معنے ہیں.افلاک کو بھی سَـمَاء کہتے ہیں.اس وسیع فضاء
Page 18
کو بھی سَـمَاء کہتے ہیں جو قبہ عظیمہ کی طرح زمین کا احاطہ کئے ہوئے ہے.اور اس میں سورج چاند اور ستارے ہیں.نیز ہر وہ چیز جو اونچی ہو اور سایہ کرے اس کو بھی سَـمَاء کہتے ہیں اور بادلوں کو بھی سَـمَاء کہتے ہیں اور بعض اوقات بارش کو بھی سَـمَاء کہہ دیتے ہیں (اقرب) رَجْعٌ.رَجْعٌ کے معنے ہیں اَلْمَطَرُ بَعْدَ الْمَطَرِ یعنی وہ بارش جو لَوٹ لَوٹ کر آتی ہے (اقرب)اور اَلصَّدْعُ کے معنے ہیں.اَلشَّقُّ فِیْ شَیْءٍ صُلْبٍ کسی سخت چیز میں اس کے پھٹنے کا نشان.اسی طرح صَدْعٌ: نَبَاتُ الْاَرْضِ یعنی زمین کی روئیدگی کو بھی کہتے ہیں (اقرب) پس ذَاتُ الرَّجْعِ کے معنے ہوں گے بار بار برسنے والا بادل اور ذَاتُ الصَّدْعِ کے معنے ہوں گے پھٹنے والی چیز یا نباتات والی.تفسیر.وَ السَّمَآءِ ذَاتِ الرَّجْعِ میں سَـمَاء سے مراد فرماتا ہے ہم تمہارے سامنے آسمان کو پیش کرتے جو ذَاتُ الرَّجْعِ ہے.یہاں سَـمَاء کے معنے بدل گئے ہیں جس طرح اِذَا السَّمَآءُ انْشَقَّتْ کا اور مفہوم تھا اور اِذَاالسَّمَآءُ انْفَطَرَتْ کا اور.اسی طرح یہاں سَـمَاء کے معنے اور ہو گئے ہیں سَـمَاء کا لفظ ایک تو افلاک کے لئے استعمال ہوتا ہے دوسرے اس کے معنے بادل کے بھی ہیں.اس جگہ سَـمَاء بادل کے معنوں میں ہی استعمال ہوا ہے.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم تمہارے سامنے شہادت کے طور پر اس بادل کو پیش کرتے ہیں جو ذَاتِ الرَّجْعِ ہے.رَجْعٌ کے معنے جیسا کہ بتایا جا چکا ہے اس باد ل کے ہوتے ہیں جو بار بار برستا ہے فرماتا ہے کیا تم بادلوں کو نہیں دیکھتے کہ وہ بار بار زمین پر برستے ہیں اگر بادلوں سے پانی نہ اترے اور اگر وہ بار بار زمین پر آکر نہ برسیں تو زمین کی ترقی بالکل رک جائے بادلوں کا پانی ہی ہے جو زمین کے نشوونما اور اس کی اندرونی قابلیتوں کو ابھارنے کا باعث بنتا ہے پہلے فرمایا تھا اِنَّهٗ عَلٰى رَجْعِهٖ لَقَادِرٌ یعنی اللہ تعالیٰ انسان کو پھر ترقی دینے پر قادر ہے اور یہاں فرمایا ہے وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الرَّجْعِ بادل کو ہم بطور شہادت پیش کرتے ہیں جو بار بار برستا ہے یعنی جس طرح وہ بار بار برس کر زمین کو زندہ کرتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ بار بار نازل ہو کر دنیا کو روحانی زندگی بخشتا ہے.اسی طرح بادلوں کی مثال دے کر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ بادل آتے اور بار بار برستے ہیں اگر بادل نہ برسیں تو دنیا تباہ ہو جائے.یہی حال روحانی زندگی کا ہوتا ہے اگر خدا تعالیٰ کی طرف سے وہ لوگ کھڑے نہ ہوں جو دنیا کی اصلاح کے لئے مامور ہوتے ہیں اور الہامِ الٰہی کا پانی زمین پر نہ اترے تو لوگوں کو روحانی زندگی کبھی حاصل نہ ہو سکے.وَالْاَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ پھر تم کہتے ہو کہ خدا نے الہام تو بھیج دیا مگر دنیا اس قابل نہیں کہ وہ اس الہام کو مان
Page 19
سکے.فرماتا ہے تمہاری یہ بات بھی غلط ہے کہ دنیا الہامِ الٰہی کو قبول کرنے کی استعداد اپنے اندر نہیں رکھتی.تم زمین کی طرف دیکھو وہ کس طرح بنجر پڑی ہوتی ہے اور بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ اس میں کسی قسم کی روئیدگی کی قابلیت نہیں رہی مگر خدا نے اس کے اندر مخفی طور پر یہ قابلیت رکھی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ پھٹ کر اپنے اندر سے قسم قسم کی سبزیاں وغیرہ پیدا کر دے چنانچہ جب بارش ہوتی ہے تو ناممکن نظر آنے والی بات بھی ممکن ہو جاتی ہے اور جہاں کسی قسم کے سبزہ کا امکان نظر نہیں آتا وہاں بھی سبزہ پیدا ہو جاتا ہے صَدْعٌ کے معنے لغت میں شَقٌّ کے بھی ہیں.اور ذَاتُ الصَّدْعِ کے معنے ذَاتُ النَّبَاتِ کے بھی ہیں.پس ذَاتُ الصَّدْعِ کے معنے ہیں نبات والی زمین یا چھٹ کر روئیدگی پیدا کرنے والی چیز.فرماتا ہے یہ ایک دوسرا نظام ہے جو ہماری طرف سے دنیا میں جاری ہے ایک طرف بار بار زمین پر بادل برستا ہے اور دوسری طرف زمین میں یہ قابلیت ہوتی ہے کہ وہ بار بار سبزیاں وغیرہ پیدا کرے.اسی طرح انسانی قابلیتیں گو تمہیں مردہ دکھائی دیتی ہیں مگر الہامِ الٰہی کی بارش کے بعد انہی مردہ قلوب میں سے کئی قسم کی سبزیاں اور روئیدگیاں پیدا ہونی شروع ہو جائیں گی.اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جیسے بعض زمینیں شور ہوتی ہیں اسی طرح انسانوں میں سے بھی بعض شور ہوتے ہیں مگر الہامِ الٰہی کی بارش کے بعد اکثر لوگ ایسے نکلتے ہیں جو جلد یا بدیر مامورِ وقت کو قبول کر لیتے ہیں.اِنَّهٗ لَقَوْلٌ فَصْلٌۙ۰۰۱۴وَّ مَا هُوَ بِالْهَزْلِؕ۰۰۱۵ (اس امر پر کہ) وہ یعنی قرآن یقیناً قطعی اور آخری بات ہے.اور وہ کوئی (بے فائدہ اور) کمزور کلام نہیں.حلّ لُغات.فَصْلٌ.فَصْلٌ فَصَلَ کا مصدر ہے اور فَصَلَ الشَّیْءَ کے معنے ہوتے ہیں.قَطَعَہٗ وَاَبَانَہٗ کسی چیز کو کاٹا اور دوسرے سے علیحدہ کر دیا.نیز اَلْفَصْلُ کے معنی ہیں اَلْـحَقُّ مِنَ الْقَوْلِ پکی بات.اَلْقَضَاءُ بَیْنَ الْـحَقِّ وَالْبَاطِلِ.حق و باطل میں فرق اور فیصلہ کرنے والی چیز.کہتے ہیں قَوْلٌ فَصْلٌ اور معنے یہ ہوتے ہیں حَقٌّ لَیْسَ بِبَاطِلٍ کہ یہ بات درست ہے باطل نہیں (اقرب) اَلْھَزْلُ.اَلْھَزْلُ.ھَزَلَ کا مصدر ہے اور ھَزَلَ الرَّجُلُ کے معنے ہیں.صَارَ مَھْزُوْلًا کمزور ہو گیا.اور جب ھَزَلَ فُلَانٌ فِیْ کَلَامِہٖ کہیں تو معنے ہوں گے مَزَحَ وَھَذٰی ہنسی اور تمسخر اختیار کیا اور سنجیدگی کو چھوڑ دیا (اقرب)
Page 20
تفسیر.فرماتا ہے یہ قرآن قول فصل ہے یعنی اس کے نزول کے بعد تمہاری شکست میںکوئی روک نہیں ہوسکتی یا قول فصل سے مراد یہ ہے کہ یَفْصِلُ بَیْنَ الْـحَقِّ وَالْبَاطِلِ یعنی یہ قرآن حق اور باطل میں فرق کر دے گا.یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے آنے کے بعد بھی حق اور باطل میں فرق پیدا نہ ہو.یا ضمیر موعود کی طرف جاتی ہے اور مراد یہ ہے کہ ممکن نہیں کہ وہ موعود آئے اور دنیا میں مذکورہ بالا تغیرات نہ ہوں.یہ ایک قطعی اور حتمی امر ہے جس کا فیصلہ کیا جا چکا ہے.وَمَا ھُوَ بِالْھَزْلِ یہ کمزور اور بے فائدہ بات نہیں.اِنَّهُمْ يَكِيْدُوْنَ كَيْدًاۙ۰۰۱۶وَّ اَكِيْدُ كَيْدًاۚۖ۰۰۱۷ وہ لوگ یقیناً (اس کے خلاف) خوب داؤ پیچ کریں گے.اور میں بھی (اس کے خلاف) خوب تدبیریں کروں گا.تفسیر.یہاں پھر اس مضمو ن کو دہرا دیا گیا ہے.جو پچھلی تین چار سورتوں سے پہلے بیان ہو رہا تھا.پہلی سورتوں میں یہ بتایا گیا تھا کہ اسلام بہت بڑی ترقی حاصل کرے گا اور تمام دنیا میں پھیل جائے گا.کفّار کے منصوبے دھرے رہ جائیں گے.ان کی کوششیں اکارت جائیں گی اور اسلام بڑھتے بڑھتے دنیا کے کناروں تک پہنچ جائے گا.اس کے بعد یہ بتایا گیا تھاکہ اسلام پر ایک تنزّل کا دَور آئے گا اور پھر یہ بتایا گیا تھا کہ اس تنزّل کے بعد پھر اسلام کی ترقی کا زمانہ آئے گا اور کفر کو تباہ کیا جائے گا.یہ تمام ذکر کرنے کے بعد فرماتا ہے اِنَّھُمْ یَکِیْدُوْنَ کَیْدًا.وَّ اَکِیْدُ کَیْدًا.دیکھو ہم نے اسلام کی ساری ہسٹری بتا دی ہے کہ کس طرح اسلام غالب ہو گا پھر کس طرح اس میں کمزوریاں پیدا ہوں گی اور پھر کس طرح اس دَورِ تنزّل کے بعد ہم اسلام اور مسلمانوں کی ترقی کا سامان کریں گے اور پھر اس مذہب کو دنیا پر غالب کر کے دکھا دیں گے یہ ایک لمبا سلسلہ جو ہم نے بتایا ہے کیا مکہ کے لوگ اتنی بڑی زنجیر کو توڑ دیں گے اور کیا یہ اپنے ناپاک ارادوں میں کامیاب ہو جائیں گے.اس نے تو ابھی بڑھنا ہے پھر گھٹنا ہے.پھر بڑھنا ہے اور دنیا پر غالب آنا ہے اور مکہ کے لوگ اس خیال میں بیٹھے ہیں کہ وہ اپنی تدبیروں سے اسلام کو مٹا دیں گے.اِنَّھُمْ یَکِیْدُوْنَ کَیْدًا وہ بھی تدبیریں کرتے ہیں وَ اَکِیْدُ کَیْدًا اور میں بھی تدبیریں کروں گا.
Page 21
فَمَهِّلِ الْكٰفِرِيْنَ اَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًاؒ۰۰۱۸ پس (اے رسول) کفار کو مہلت دو انہیں کچھ (اور) مہلت دو (تا جو زور لگانا چاہیں لگا لیں).حلّ لُغات.مَھِّلْ.مَھِّلْ.مَھَّلَ سے امر کا صیغہ ہے اور مَھَّلَ کے معنے ہیں اَنْظَرَہٗ وَاَجَّلَہٗ اس کو مہلت دی (اقرب) اَمْھِلْ اَمْھَلَ کا امر ہے اور اس کے بھی وہی معنے ہیں جو مَھَّلَ کے ہیں (اقرب) نیز مَھَلَ اور اَمْھَلَ کے معنے ہیں رَفِقَ بِہٖ اس کے ساتھ نرمی اور رفق کا معاملہ کیا (اقرب) پس اَمْھِلْ اور مَھِّلْ کے معنے ہوں گے (۱)مہلت دے (۲)نرمی کا معاملہ کر.تفسیر.مَھِّلْ کے بعد اَمْھِلْھُمْ رُوَیْدًاکہنے کی وجہ اس آیت میں ایک لطیف اشارہ کیا گیا ہے.اللہ تعالیٰ یوں بھی کہہ سکتا تھا کہ فَمَھِّلِ الْکٰفِرِیْنَ رُوَیْدًا مگر بیان کی لطافت اور اس کی خوبی اس سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بجائے فَمَھِّلِ الْکٰفِرِیْنَ رُوَیْدًا کے فَمَھِّلِ الْکٰفِرِیْنَ اَمْھِلْھُمْ رُوَیْدًا فرمایا.پہلے فرمایا کہ فَمَھِّلِ الْکٰفِرِیْنَ کافروں کو مہلت دے اس سے دو کیفیتیں پیدا ہوتی تھیں.ایک مومنوں کے قلب میں اور ایک کفار کے قلب میں.مومنوں کے قلب میں تو اس سے یہ کیفیت پیدا ہوتی تھی کہ نہ معلوم کفار کو یہ مہلت کب تک دی جائے گی اور کفار کے دل میں یہ کیفیت پیدا ہوتی تھی کہ ابھی کوئی فکر کی بات نہیں ہمیں اور مہلت مل گئی ہے.اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کیفیتوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے فرما دیا.اَمْھِلْھُمْ رُوَیْدًا اس طرح مومنوں کی بھی دلجوئی کر دی کہ کفار کو کوئی لمبی مہلت نہیں دی جائے گی بلکہ بہت تھوڑی مہلت دی جائے گی اور ادھر کفار کی امید توڑ دی کہ تم یہ خیال مت کرو کہ تمہیں اور ڈھیل دی جائے گی تمہاری تباہی اور بربادی کا وقت اب بالکل قریب آپہنچا ہے.محاورہ میں کہتے ہیں سَارُوْا سَیْرًا رُوَیْدًا اَیْ بِرِفْقٍ پس اَمْھِلْھُمْ رُوَیْدًا کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ ان کو تھوڑی مدت تک مہلت دے.اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ ایام مہلت میں ان سے رفق کا معاملہ کرو کیونکہ آخر ان کی سزا کا وقت آنے والا ہے اس وقت ان کی تباہی کے سامان اللہ تعالیٰ خود اپنے ہاتھوں سے کرے گا.
Page 22
سُوْرَۃُ الْاَعْلٰی مَکِّیَّۃٌ سورۃ الاعلیٰ.یہ سورۃ مکی ہے وَھِیَ تِسْعَ عَشْـرَۃَ اٰیَۃً دُوْنَ الْبَسْمَلَۃِ وَ فِیْـھَا رُکُوْعٌ وَّاحِدٌ اور اس کی بسم اللہ کے سوا انیس آیتیں ہیں اور ایک رکوع ہے سورۃ الاعلیٰ مکی ہے یہ سورۃ جمہور کے نزدیک مکی ہے.حضرت ابن عباسؓ، ابنِ زبیرؓ اور حضرت عائشہؓ بھی فرماتی ہیں کہ یہ مکی ہے.بخاری اور دوسری کتبِ احادیث میں حضرت براء بن عاذبؓ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کے صحابہؓ میں سے سب سے پہلے مصعب ابن عمیرؓ اور عبداللہ بن ام مکتومؓ مدینہ تشریف لائے اور انہوں نے ہمیں قرآن مجید سکھانا شروع کیا.ان کے بعد عمارؓ اور بلالؓ اور سعدؓ آئے پھر عمر ابن خطابؓ بیس۲۰ صحابہؓ سمیت آئے.پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم آئے اور میں نے مدینہ والوں کو کسی بات پر اتنا خوش ہوتے نہیں دیکھا جتنا رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم کی تشریف آوری پر ان کو خوش دیکھا.یہاں تک کہ بچے بھی خواہ وہ چھوٹے تھے یا بڑے جب آپس میں ملتے تو نہایت خوشی کے ساتھ ایک دوسرے سے کہتے دیکھو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے.دیکھو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگئے اور جب آپؐتشریف لائے تو میں نے اس وقت سورۃ الاعلیٰ اور اسی قسم کی بعض اور سورتیں یاد کی ہوئی تھیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورۃ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے سے پہلے نازل ہو چکی تھی.یورپین مصنّفین بھی اس طرف گئے ہیں کہ یہ سورۃ مکہ میں نازل ہو چکی تھی.چنانچہ جرمن محقق نولڈکے اسے سورۂ نون کے معاً بعد نازل ہونے والی سورۃ قرار دیتا ہے.پادری ویری کا سورۂ اعلیٰ کی بعض آیات کے مدنی ثابت کرنے کے متعلق بے ہودہ استدلال پادری ویری نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ اس کی سترہو۱۷یں، اٹھارو۱۸یں اور انیسو۱۹یں آیتیں مدنی ہیں کیونکہ ان آیتوں میں حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہم السلام کی کتب کا ذکر کیا گیا ہے اور ان انبیاء سے مدینہ میں جا کر آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم یہودیوں سے ملنے کی وجہ سے ہی روشناس ہوئے تھے.لیکن یہ استدلال پادری ویری کے مخصوص استدلالوں
Page 23
کی قسم کا ہی ہے.کیونکہ مکی سورتوں میں متعدد مقامات پر پرانے انبیاء کا ذکر آتا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تو قریش کے جدِّ امجد تھے ان کے ذکر سے یہ قیاس کر لینا کہ مدینہ میں جا کر یہودیوں کی صحبت کے نتیجہ میں اسے بیان کیا گیا ہے انتہائی طور پر عقل سے گری ہوئی بات ہے.اس سورۃ کے متعلق مسند احمد، مسلم اور دوسری کتبِ احادیث میں نعمان ابن بشیرؓ سے روایت آتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم جمعہ اور عیدین کی نمازوں کی پہلی رکعت میں یہ سورۃ پڑھا کرتے تھے اور دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ تلاوت فرمایا کرتے تھے بلکہ اگر عید اور جمعہ اکھٹے ہو جاتے تب بھی آپؐیہی د۲و سورتیں دونوں نمازوں میں پڑھا کرتے تھے.ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ، دارقطنی، بیہقی اور حاکم میں ابی ابن کعبؓ سے روایت آتی ہے.کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم نمازِ وتر کی پہلی رکعت میں یہ سورۃ تلاوت فرماتے تھے دوسری رکعت میں سورۃ الکافرون اور تیسری رکعت میں سورۃ الاخلاص تلاوت فرمایا کرتے تھے.(سنن ابی داؤد کتاب الصلاۃ باب ما یقرأ فی الوتر) حضرت علیؓ سے مسند احمد میں روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم اس سورۃ کو بہت محبوب سمجھتے تھے.(مسند احمد بن حنبل بروایت حضـرت علی رضی اللہ عنہ) ابوداؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، حاکم اور بیقہی میں حضرت عائشہؓ سے بھی روایت آتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم وتر کی پہلی رکعت میں یہ سورۃ دوسری رکعت میں سورۃ الکافرون اور تیسری رکعت میں سورۃ الاخلاص اور معوّذتین پڑھا کرتے تھے.( ترمذی ابواب الوتر باب ماجاء ما یقرأ فی الوتر) سورۃ الاعلیٰ کا تعلق پہلی سورۃ سے اس سورۃ کا تعلق پہلی سورۃ سے بحرِ محیط کے مصنف تو یہ بتاتے ہیں کہ پہلی سورۃ میں ذکر تھا کہ انسان کی پیدائش اس اس طرح ہوئی ہے.اس کا جواب کہ اسے اس طرح کس نے پیدا کیا ہے سورۃ الاعلیٰ میں دیا گیا ہے کہ اسے ربّ الاعلیٰ نے پیدا کیا ہے.لیکن میرے نزدیک اس سورۃ کا پہلی سورۃ سے تعلق یہ ہے کہ اس سورۃ میں یہ مضمون بیان کیا گیا تھا کہ آنے والا موعود جہاں یہ خصوصیت رکھتا ہوگا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم کے نور کو اپنے اندر جذب کر کے اسے دوسرے لوگوں تک پہنچائے یعنی اس کی حیثیت بدر کی سی ہو گی اور وہ چودھویں کے چاندکی طرح دنیا میں اسلامی نور کو پھیلائے گا وہاں وہ طارق بھی ہو گا.طارق کہتے ہیں صبح کے ستارے کو اور صبح کا ستارہ سورج کے طلوع کی طرف اشارہ کرتا ہے.یعنی صرف یہی نہیں کہ اس کے ذریعہ سے لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں گے بلکہ اس پر ایمان لانے کی وجہ سے بنی نوع
Page 24
انسان کو ذاتی طور پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا تعلق پیدا ہو جائے گاکہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار اور آپؐکی برکات کو اپنے نفوس میں بھی دیکھنے لگ جائیں گے.یہی وجہ ہے کہ آنے والے موعودؑ کے د۲و نام رکھے گئے تھے.ایک مسیحؑ جو اس کے بدر ہونے کی علامت ہے اور دوسرا مہدیؑ جو اس کے طارق ہونے کی علامت ہے.یہ د۲و نام اس کے دو مختلف کاموں کی طرف اشارہ کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اپنے اندر جذب کر کے لوگوں تک پہنچائے گا اور پھر لوگوں میں ایسی استعداد پیدا کر دے گا کہ ان کے تعلقات براہِ راست رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم سے ہو جائیں گے.پس وہ اپنے ایک کام کے لحاظ سے بدر ہو گا اور دوسرے کام کے لحاظ سے طارق ہو گا.یہاں ایک سوال پیدا ہوتا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم تو کامل نبی ہیں اور آپؐپر وہ کلام نازل ہوچکا ہے جو آخری اور قطعی کلام ہے جیسا کہ پہلی سورۃ میں بھی بتایا گیا ہے کہ اِنَّہٗ لَقَوْلٌ فَصْلٌ رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم پر جو کلام نازل ہوا ہے وہ قولِ فصل ہے اور قولِ فصل کے معنے ہوتے ہیں وہ کلام جو باقی تمام چیزوں کو قطع کر دیتا ہے یعنی ایسا کلام جو سب سے اعلیٰ اور فائق ہو وہ قولِ فصل کہلاتا ہے.اسی طرح اس کے یہ بھی معنے ہوتے ہیں کہ وہ کلام جس کے بعد کسی اور کلام کی ضرورت نہیں رہتی.جیسے قرآن مجید میں حضرت داؤد علیہ السلام کی نسبت آتا ہے وَشَدَدْنَا مُلْكَهٗ وَ اٰتَيْنٰهُ الْحِكْمَةَ وَ فَصْلَ الْخِطَابِ (صٓ:۲۱) یہاں فصل الخطاب کے معنے یہی ہیں کہ اس کا فیصلہ آخری تھا.پس فصل کے معنے ہوئے وہ آخری اور کامل کلام جس کے بعد کسی اور کلام کی ضرورت نہیں رہتی.ان معنوں کے لحاظ سے سوال پیدا ہوتا تھا کہ قرآن کریم جب قولِ فصل ہے یعنی آخری اور کامل کلام ہے جس کے بعد کسی اور کلام کی ضرورت نہیں رہتی تو پھر آنے والے موعود کی کیا ضرورت ہے.جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی قولِ فصل ہے اور آپؐپر نازل شدہ شریعت اس قدر کامل ہے کہ اس کے بعد کسی اور شریعت کی دنیا کو ضرورت نہیں تو پھر آپؐکے بعد کسی اور الہام کی کیا ضرورت ہوئی.پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ وَمَا ھُوَ بِالْھَزْلِ یہ شریعت کمزور ہونے والی نہیں.ھَزْلٌ کے معنے ضعیف اور ناطاقت اور کمزور اور ناکارہ کے ہوتے ہیں اِنَّہٗ لَقَوْلٌ فَصْلٌ کے معنے تو یہ تھے کہ یہ ایسا کلام ہے جس کے بعد کسی اور کلام کی ضرورت نہیں.اپنی ذات میں یہ کامل کلام ہے لیکن کامل تعلیم بھی چونکہ بعض دفعہ مٹ جایا کرتی ہے اس لئے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وَمَا ھُوَ بِالْھَزْلِ یہ ضعیف اور ناکارہ ہونے والا کلام نہیں کہ تم یہ شبہ کر سکو کہ شائد یہ کلام بھی کسی دن مٹ جائے گا.اگر محض قولِ فصل تک بات کو ختم کر دیا جاتا تو اس شبہ کا ازالہ نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ بعض کلام قولِ فصل تو ہوتے ہیں مگر بوجہ وقتی ہونے کے
Page 25
کچھ عرصہ کے بعد مٹ جاتے ہیں جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کی نسبت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اٰتَيْنٰهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ ہم نے اسے حکمت اور فصل الخطاب دیا مگر اس کے باوجود وہ کلام مٹ گیا.پس قولِ فصل سے یہ ثابت نہیں ہوتا تھا کہ قرآن کریم وقتی طور پر قولِ فصل ہے یا ہمیشہ کے لئے قولِ فصل ہے بلکہ یہ شبہ پیدا ہو سکتا تھا کہ آخری کلام کے معنے یہ کیوں نہ سمجھ لئے جائیں کہ قرآن کریم صرف اپنے زمانہ کے لئے کامل تھا اور بوجہ سابق کتب کو منسوخ کر دینے کے اس وقت کے لئے آخری تھا جیسا کہ بہائی کہتے ہیں جب نئی ضرورتیں پیدا ہوں گی اس وقت کوئی نئی کتاب آ جائے گی.(God Passes: by Shoghi Effendi, page25) سورۂ اعلیٰ میں اس بات کا ذکر کہ قرآن مجید کی موجودگی میں اور الہام کی کیا ضرورت ہے اس شبہ کا ازالہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا ھُوَ بِالْھَزْلِ یہ ضعیف اور ناکارہ ہونے والا کلام نہیں.اس کی ضرورت دنیا سے کبھی محو نہیں ہو گی اور یہ کتاب کبھی مٹ نہیں سکے گی.پس مَا ھُوَ بِالْھَزْلِ نے بتا دیا کہ یہ کلام وقتی طور پر فصل نہیں بلکہ ہمیشہ کے لئے قولِ فصل ہے.اور جب یہ کلام آخری کلام ہے کامل کلام ہے اور ساتھ ہی کمزور ہونے والا نہیں تو سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ اس کلام کی موجودگی میں کسی اور کلام کی ضرورت ہی کیا ہے.یہ کتاب کامل بھی ہے اور یہ کتاب کمزور بھی کبھی نہیں ہو گی تو پھر کسی اور کلام یا کسی اور مدعیٔ الہام کی کیا ضرورت ہوئی.اسی طرح پہلی سورۃ میں بتایا گیا تھا کہ خُلِقَ مِنْ مَّآءٍ دَافِقٍ انسان کی پیدائش مَآءٍ دَافِقٍ یعنی اچھلنے والے پانی سے ہوئی ہے.یہاں اللہ تعالیٰ صرف مَآءٍ کا لفظ بھی استعمال فرما سکتا تھا جیسے بعض دوسرے مقامات پر انسانی پیدائش کے متعلق صرف مَآءٍ کا لفظ استعمال ہوا ہے.دَافِقٍ کا لفظ اس کے ساتھ استعمال نہیں ہوا.مگر یہاں اللہ تعالیٰ نے بجائے مَآءٍ کا لفظ استعمال کرنے کے مَآءٍ دَافِقٍ کے الفاظ استعمال کئے ہیں.درحقیقت ان الفاظ کے ذریعہ اس امر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جس طرح ظاہری طور پر نطفہ میں دفق کی خاصیت ہوتی ہے اور وہ اچھل کر باہر نکلتا ہے اسی طرح باطن میں بھی انسان کے اندر اچھلنے کودنے کی خاصیت رکھی گئی ہے.گویا اس کی ظاہری پیدائش سے اس کی باطنی پیدائش ملتی جلتی ہے.جس طرح ظاہر میں وہ اچھلنے والے مادہ سے پیدا ہوا ہے اسی طرح روحانی طور پر بھی اس میں اچھال پیدا ہوتا ہے اور اس پر ترقی کے مختلف دَور آتے ہیں.وہ بڑھتا ہے گھٹتا ہے.بڑھتا ہے گھٹتا ہے.بڑھتا ہے گھٹتا ہے.یہ قول بھی اِنَّہٗ لَقَوْلٌ فَصْلٌ سے ٹکراتا تھا اور سوال پیدا ہوتا تھا کہ خُلِقَ مِنْ مَّآءٍ دَافِقٍ میں تو اس امر کی طرف اشارہ کیا گیا تھاکہ انسانی پیدائش اچھلنے والے پانی سے ہوئی ہے جس کے معنے یہ تھے کہ انسان کی روحانی پیدائش بھی اچھلنے والے مادہ سے ہے اور اس پر ترقی اور تنزّل کے مختلف دَور
Page 26
آتے ہیں.مگر یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن قولِ فصل ہے.جب یہ قول فصل ہے تو پھر بڑھنے اور گھٹنے کے کیا معنے ہوئے.اس کلام کے نزول کے بعد انسان کو ہمیشہ بڑھنا ہی چاہیے گھٹنا نہیں چاہیے.مگر ادھر تو تم بتا رہے ہو کہ جس طرح انسان ظاہر میں مَآءٍ دَافِقٍ سے پیدا ہوا ہے اسی طرح باطن میں بھی مَآءٍ دَافِقٍ سے پیدا ہواہے.ایک رو ہے جو اس کے اندر پائی جاتی ہے کبھی وہ رو ترقی کی طرف چلی جاتی ہے اور کبھی تنزّل کی طرف.اچھلنے والی چیز کے معنے یہی ہوتے ہیں کہ وہ کبھی گرتی ہے کبھی اچھلتی ہے کبھی اوپر کی طرف چلی جاتی ہے اور کبھی نیچے کی طرف چلی جاتی ہے.پس مَآءٍ دَافِقٍ میں یہ اشارہ کیا گیا تھا کہ بنی نوع انسان کی پیدائش ایسے رنگ میں ہوئی ہے کہ کبھی قوم آگے کی طرف بڑھ جاتی ہے کبھی پیچھے کی طرف اپنا قدم ہٹا لیتی ہے.کبھی ترقی کی طرف اپنا قدم بڑھا لیتی ہے کبھی تنزّل میں گر جاتی ہے.گویا انسانی پیدائش دفق کا رنگ اپنے اندر رکھتی ہے اور مختلف ویوزWAVESاور لہریں ہیں جو اس کے اندر پائی جاتی ہیں.لیکن دوسری طرف بتایا جاتا ہے کہ یہ قولِ فصل ہے جس کے معنے یہ ہیں کہ قولِ فصل کے بعد یہ لہر نیچے کی طرف نہیں جا سکتی.جب قول فصل کے بعد یہ رو نیچے کی طرف نہیں جا سکتی تو پھر خُلِقَ مِنْ مَّآءٍ دَافِقٍ کا کیا مفہوم ہوا.اگر اس کے بعد انسانی زندگی میں دفق نہیں پایا جائے گا تو قرآن کریم کی یہ آیت غلط ٹھہرتی ہے.اور اگر اس میں دفق پایا جائے گا تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ آئندہ دفق کس رنگ میں ہو گا.جیسا کہ میں آگے چل کر بتاؤں گا خُلِقَ مِنْ مَّآءٍ دَافِقٍ اور اِنَّہٗ لَقَوْلٌ فَصْلٌ کی آیات سے جو سوالات پیدا ہوتے تھے ان کا اس سورۃ میں جواب دیا گیا ہے.پھر اِنَّہٗ لَقَوْلٌ فَصْلٌ کے متعلق یہ سوال بھی پیدا ہوتا تھا کہ ابتدائے عالم سے اب تک دنیا میں کئی انبیاء گذر چکے ہیں ان میں سے کسی نبی پر پہلے یہ قولِ فصل کیوں نازل نہیں ہوا اور کیوں اب قولِ فصل نازل ہوا ہے.گویا جہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قولِ فصل کے بعد کسی موعود کی کیا ضرورت ہے وہاں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ قولِ فصل کا نزول اگر بنی نوع انسان برداشت کر سکتے ہیں تو یہ قولِ فصل پہلے کیوں نہ نازل کر دیا گیا اور اب کیوں نازل کیا گیا ہے.غرض دو سوال قولِ فصل سے اور ایک سوال خُلِقَ مِنْ مَّآءٍ دَافِقٍ سے پیدا ہوتا تھا اس سورۃ میں اللہ تعالیٰ ان سوالات کا جواب دیتا ہے اور لوگوں کو بتاتا ہے کہ قانونِ قدرت سے یہ دونوں امور ظاہر ہیں کہ بعض اشیاء عارضی فوائد کے لئے پیدا کی جاتی ہیں اور بعض اشیاء لمبے فوائد کے لئے پیدا کی جاتی ہیں.جو اشیاء عارضی اغراض کے لئے پیدا کی جاتی ہیںان کی زندگی بہت تھوڑی ہوتی ہے لیکن جو اشیاء انتہائی کمال کے اظہار کے لئے پیدا کی جاتی ہیں ان کی زندگی بہت لمبی ہوتی ہے یا ان کا جسمانی ارتقاء بند ہو جاتا ہے.خَلق کے لحاظ سے اس سورۃ کا پہلی سورۃ سے ایک تعلق ہے اور وہ یوں کہ پہلی سورۃ میں انسانی پیدائش کا ذکر
Page 27
کیا گیا تھا اور بتایا گیا تھا کہ اس کی ترقی تدریجی ہوتی ہے.چنانچہ سورۂ طارق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا يَخْرُجُ مِنْۢ بَيْنِ الصُّلْبِ وَ التَّرَآىِٕبِ وہ پہلے صُلب میں سے آتا ہے اور پھر ترائب اس کو ترقی دیتے ہیں.یعنی پہلے باپ کے جسم میں نطفہ بنتا ہے.پھر ماں کے رحم میں اس نطفہ کی پرورش ہوتی ہے اور پھر پیدائش کے بعد ماں کی چھاتیوں سے وہ غذا حاصل کر کے آہستہ آہستہ نشوونما حاصل کرتا ہے.گویا انسانی پیدائش کا ذکر کرتے ہوئے اس کی تدریجی ترقی کی طرف اشارہ کیا گیا تھا.اس سورۃ میں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ جس طرح انسان کی ظاہری ترقی تدریجی ہوتی ہے اسی طرح اس کی روحانی ترقی بھی تدریجی ہوتی ہے.یوں تو انسان ایک ہی قسم کے قویٰ لے کر پیدا ہوا ہے مگر تجربہ کی مدد سے انسانی دماغ مزید نشوونما پاتا جاتا ہے.گویا جس طرح انسان کی جسمانی پیدائش تدریجی رنگ میں ہوتی ہے اسی طرح اس کی روحانی پیدائش بھی تدریجی رنگ میں ہوتی ہے.اور جس طرح فرد کی پیدائش تدریجی منازل کو طے کرنے کے بعد ہوتی ہے اسی طرح قوم کی پیدائش بھی تدریجی منازل کوطے کرنے کے بعد ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ قومی دماغ ترقی کرتا ہے.یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر زمانہ کے لحاظ سے ہدایت آتی رہی ہے مگر جس طرح سبزیاں اور ترکاریاں ضروری تو ہیں مگر ان کی ضرورت کا زمانہ تھوڑا ہوتا ہے پس وہ جلد فنا ہو جاتی ہیں.اسی طرح وہ شرائع بھی ضائع ہوتی رہیں لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جن کی ضرورت عارضی نہیں بلکہ مستقل ہوتی ہے.وہ جب سے پیدا ہوئی ہیں اسی رنگ میں چلتی چلی جاتی ہیں.مثلاً سورج ہے یہ جب سے پیدا ہوا ہے اس وقت سے لے کر اب تک اسی صورت میں چلا جا رہا ہے یہ نہیں ہوتا کہ ایک سورج مٹ جائے تو اس کی جگہ دوسرا سورج پیدا ہو جائے یا مثلًا چاند ہے جب سے یہ پیدا ہوا ہے اس وقت سے لے کر اب تک قائم چلا آ رہا ہے.غرض مخلوق کے دائرہ میں جہاں بعض اشیاء ایسی ہیں جن پر تباہی آئی اور وہ مٹ گئیں وہاں بعض اشیاء ایسی بھی ہیںجن پر تباہی نہیں آئی.چنانچہ مسئلہ ارتقاء کے ماتحت محققین نے یہ تسلیم کیا ہے کہ بعض ناقص پیدائشیں بالکل معدوم ہو گئی ہیں.مگر جب انسان پیدا ہو گیا تو یہ ارتقائی تغیّر بند ہو گیا.پس محض اس بات پر اپنے اعتراض کی بنیاد رکھنا کہ جو چیز پیدا کی گئی ہے اسے فنا نہیں ہونا چاہیے بالکل غلط اور باطل اصول ہے.خدا تعالیٰ کی طرف سے کئی چیزیں پیدا کی جاتی ہیںوہ ضروری اور فائدہ بخش بھی ہوتی ہیں.مگر کچھ عرصہ کے بعد وہ فنا بھی ہو جاتی ہیں کیونکہ زمانہ تبدیل ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں دنیا کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں رہتی.مگر اس پر پھر ایک اور سوال پیدا ہوتا تھا اور وہ یہ کہ تمہارے پاس اس بات کا ثبوت کیا ہے کہ قرآن کبھی منسوخ نہیں ہو گا.تم تسلیم کرتے ہو کہ تورات آئی.وہ اپنے زمانہ کے لئے نہایت ضروری کتاب تھی مگر کچھ عرصہ کے بعد منسوخ ہو گئی.پھر
Page 28
کیوں نہ قرآن کریم کے متعلق بھی یہی بات تسلیم کر لی جائے کہ بے شک یہ ضروری ہے مگر صرف اپنے زمانہ کے لئے.ہمیشہ کے لئے نہیں.چنانچہ بہائی یہی کہتے ہیں کہ جب باقی شریعتیں منسوخ ہو گئیں تو تم یہ کس طرح کہہ سکتے ہو کہ قرآن کبھی منسوخ نہیں ہو گا.اس سوال کا بھی اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ میں جواب دیا ہے اور بتایا ہے کہ ہم تمہارے سامنے اس بات کا ثبوت پیش کرتے ہیں کہ کیوں پہلی شریعتیں منسوخ ہوئیں اور کیا دلیل ہے اس بات پر کہ قرآن کبھی منسوخ نہیں ہو گا.آخری موعود کے ذریعہ خدا تعالیٰ کی تین قسم کی تسبیحیں یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ جن سورتوں میں مسیح موعودؑ کا ذکر آتا ہے ان میں تسبیح کا خاص طور پر ذکر آتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسیح موعودؑ کے ساتھ تسبیح کا کوئی خاص جوڑ ہے.یہ تو نہیں کہ جہاں بھی مسیح موعودؑ کا ذکر آیا ہو وہاں تسبیح کا بھی ذکر ہو بلکہ وہ سورتیں جن میں خصوصیت کے ساتھ مسیح موعودؑ کا ذکر کیا گیا ہے ان سورتوں میں تسبیح کا بھی خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے.چنانچہ مسیح موعودؑ کا خاص طور پر ذکر سورۂ صف، سورۂ جمعہ اور سورۃ الاعلیٰ میں آتا ہے.بعض اور سورتیں بھی ہیں جن میں مسیح موعودؑ کا ذکر آتا ہے جیسے اس سے پہلی تین چار سورتوں کی تفسیر میں بیان ہو چکا ہے لیکن ان تین سورتوں میں خصوصیت کے ساتھ مسیح موعودؑ کا ذکر آتا ہے.ان میں سے سورۂ صف کو سَبَّحَ سے شروع کیا گیا ہے.چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے.سَبَّحَ لِلّٰہِ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ وَھُوَ الْعَزِیْزُ الْحَکِیْمُ.پھر سورۂ جمعہ کو یُسَبِّحُ سے شروع کیا گیا ہے.فرماتا ہے یُسَبِّحُ لِلّٰہِ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ الْمَلِکِ الْقُدُّوْسِ الْعَزِیْزِ الْحَکِیْمِ.اور سورۃ الاعلیٰ کو سَبِّحْ سے شروع کیا گیا ہے.فرماتا ہے سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى.گویا تینوں افعال کا استعمال کیا گیا ہے.ماضی، مستقبل اور امر.سَبَّحَ خالص ماضی پر دلالت کرتا ہے.یُسَبِّحُ حال اور استقبال دونوں پر دلالت کرتا ہے.کیونکہ مضارع کے معنوں میں حال کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے اور استقبال کا بھی.اور امر ہمیشہ استقبال کے متعلق ہوتا ہے.جب ہم کسی کو کہتے ہیں تو ایسا کر تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کام کو اس وقت نہیں کر رہا بلکہ ہمارے کہنے کے بعد کرے گا.پس امر ہمیشہ استقبال کے زمانہ پر دلالت کرتا ہے.پس ان تین صیغوں یعنی ماضی، مضارع اور امر کو استعمال کر کے تینوں زمانوں کی تسبیح مسیح موعودؑ کے ذکر میں بیان کی گئی ہے یعنی تینوں قسم کی تسبیحیں اس کے زمانہ میں ہوں گی.ماضی کی بھی، حال کی بھی اور استقبال کی بھی.یہ ایک علیحدہ مضمون ہے جس کو تفصیلی طور پر یہاں بیان نہیں کیا جا سکتا.میں نے صرف اشارہ کر دیا ہے کہ ان تینوں سورتوں میں تین افعال استعمال کئے گئے ہیں اور اس طرح مسیح موعودؑ کے ذریعہ سے تسبیح کی تکمیل کا وعدہ کیا گیا ہے.
Page 29
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۰۰۱ (میں) اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا (اور) بار بار رحم کرنے والا ہے (شروع کرتا ہوں) سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَىۙ۰۰۲ (اے خاتم النبین) اپنے بزرگ (وبرتر) رب کے نام کا بے عیب ہونا بیان کر.حلّ لُغات.سَبِّحْ.سَبِّحْ امر کا صیغہ ہے اور سَبَّحَ کے معنے ہوتے ہیں اس نے اسے نقص سے پاک قرار دیا (اقرب) پس سَبِّحْ کے معنے ہوئے نقص سے پاک قرار دے.رَبٌّ کے معنے ہوتے ہیں وہ ذات جو تدریجی طور پر ترقی دیتے ہوئے کمال تک پہنچاتی ہے.گویا پیدا کرنا اور پھر تدریجی طور پر ترقی دیتے ہوئے کمال تک پہنچانا یہ سب کچھ ربّ کے مفہوم میں شامل ہے.تفسیر.سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى میں اعلیٰ لانے کی وجہ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰىکے معنے ہیں تو تسبیح کر اپنے رب کے نام کی جو اعلیٰ ہے.یا اپنے رب کے اعلیٰ نام کی تسبیح کر.یہاں اعلیٰ صفت رب بھی ہو سکتا ہے اور صفت اسم بھی.یعنی یہ بھی معنے ہو سکتے ہیں کہ اپنے رب کے اسم کی جو اعلیٰ ہے تسبیح بیان کر اور یہ معنے بھی ہو سکتے ہیں کہ اپنے اعلیٰ رب کے نام کی تسبیح بیان کر.رب کی صفت قرار دینے کی صورت میں اس کے یہ معنے ہوں گے کہ تیرا رب جو اعلیٰ ہے یعنی تیرا رب جس کی ربوبیت سب سے بلنداور ارفع شان رکھتی ہے اس کی تسبیح بیان کر.اور اسم کی صفت ہونے کی صورت میں آیت کے یہ معنے ہوں گے کہ تو اپنے رب کے سب سے بلند نام کی تسبیح کر اور مطلب یہ ہو گا کہ تو اپنے رب کا نام دنیا میں بلند کر.بات یہ ہے کہ ربوبیت کے لحاظ سے کئی لوگ خدا تعالیٰ کے شریک ہوتے ہیں جیسے ماں باپ ہیں کہ وہ بھی ایک قسم کے رب ہوتے ہیں کیونکہ بچوں کی ربوبیت کرتے ہیں.اسی لئے قرآن کریم میں رب کا لفظ غیر اللہ کی نسبت بھی استعمال کیا گیا ہے.اور اس طرح تسلیم کیا گیا ہے کہ اور لوگوں کو بھی نام کے لحاظ سے خدا تعالیٰ کی اس صفت میں اشتراک حاصل ہے.چنانچہ ماں باپ ایک قسم کے رب ہوتے ہیں کیونکہ وہ بچوں کی ربوبیت کرتے ہیں.استاد بھی ایک قسم کا رب ہوتا ہے.مذہبی پیشوا بھی ایک قسم کا رب ہوتا ہے.اسی طرح محسن انسان بھی ایک
Page 30
قسم کا رب ہوتا ہے.اور یہ سب اپنے اپنے دائرہ میں دوسروں کی ربوبیت کرتے ہیں.پس چونکہ اور لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی صفتِ ربوبیت میں شریک ہوتے ہیں اس لئے یہاں صرف رب کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا بلکہ رب کے ساتھ اعلیٰ کا بطور صفت ذکر کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ گو اور لوگوں کو بھی نام کے لحاظ سے اس صفت میں اشتراک حاصل ہوتا ہے مگر تیرا رب وہ ہے جو اعلیٰ ہے اور دوسروں کے رب وہ ہیں جو ادنیٰ ہیں.ان کی ربوبیتیں سخت ناقص ہوتی ہیں مگر خدا تعالیٰ کی ربوبیت ہر لحاظ سے کامل ہوتی ہے.پس سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى فرما کر حکم دیا کہ خدا تعالیٰ کی ربوبیت پر جو اعتراضات وارد ہوتے ہیں ان کو تودور کر کیونکہ فعل میں ایک ناقص اشتراک ہونے کی وجہ سے دوسری ناقص ربوبیتوں کو دیکھتے ہوئے جو اعتراضات پیدا ہوتے ہیں لوگ ان کو خدا تعالیٰ کی طرف بھی منسوب کر دیتے ہیں یا سمجھ لیتے ہیں کہ خدا تعالیٰ بھی ایسا ہی کرتا ہو گا.پس اشتراک نام سے جو اشتباہ پیدا ہوتا ہے اور خدا تعالیٰ کی نسبت غلط خیالات لوگوں میں پھیل جاتے ہیں تو ان کو دور کر.جیسے ناقص تربیت کرنے والا استاد گو مربّی ہوتا ہے مگر بعض دفعہ بجائے مفید ہونے کے اس کی تربیت کئی قسم کے نقائص پیدا کرنے کا موجب بن جاتی ہے.یا ماں باپ کھانا کھلاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، کپڑے پہناتے ہیں، ہر قسم کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں مگر بعض دفعہ لاڈ اور چاؤ میں بچوں کے اخلاق بگاڑ دیتے ہیں.پس بے شک وہ بھی رب ہیں مگر ان کی ربوبیت بعض دفعہ ناقص ثابت ہوتی ہے اور انسان بجائے فائدہ اٹھانے کے کئی قسم کی خرابیوںمیں مبتلا ہو جاتا ہے.مگر فرماتا ہے ہماری ربوبیت میں کسی قسم کا نقص نہیں اس لئے تو لوگوں کو بتا کہ بے شک ربوبیت کے نام میں لوگ خدا تعالیٰ کے شریک ہو جاتے ہیںلیکن جس خدا کو میں پیش کرتا ہوں وہ اعلیٰ ہے اس کی ربوبیت کے کسی شعبہ میں بھی نقص نہیں پایا جاتا.وہ اگر تعلیم دیتا ہے تو غیر ناقص تعلیم دیتا ہے.سامان مہیا کرتا ہے تو ایسے سامان ہی مہیا کرتا ہے جو ضروری ہوتے ہیں ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ اس کی ربوبیت ناقص ہو.جن سامانوں کی ضرورت ہو وہ مہیا نہ کرے یا جن سامانوں کی ضرورت نہ ہو ان کو مہیا کر دے.ماں باپ کی تربیت میں یہ نقص ہوتا ہے کہ وہ بعض دفعہ صحیح ضرورت کو نہیں پہچانتے.ایسے وقت میں غذا دے دیتے ہیں جب غذا دینے کی ضرورت نہیں ہوتی.یا اس وقت بچے کو غذا نہیں دیتے جب اسے غذا کی ضرورت ہوتی ہے.بچے زیادہ تر اسی لئے بیمار ہوتے ہیں کہ ماں باپ ان کی غور وپرداخت اور پرورش میں غلطیوں کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں.بعض دفعہ بچے کو دودھ کی ضرورت ہوتی ہے مگر ماں اسے دودھ نہیں پلاتی.نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کمزور اور نحیف ہو جاتا ہے اور بعض دفعہ اسے دودھ کی ضرورت نہیں ہوتی مگر ذرا سا رونے پروہ اسے دودھ پلانا شروع کر دیتی ہے جس سے اس کے معدہ میں کئی قسم کی خرابیاں
Page 31
پیدا ہو جاتی ہیں یا بعض دفعہ بچہ ایسی عمر کو پہنچ جاتا ہے جب اسے ٹھوس غذا کھلانی چاہیے مگر ماں اسے دودھ ہی پلاتی جاتی ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ بھی کمزور ہو جاتی ہے اور بچہ بھی ٹھوس غذا کو ہضم کرنے کی قوت کو کھو بیٹھتا ہے.دودھ ہمیشہ کے لئے غذا نہیں بلکہ صرف ایک وقت تک کےلئے غذا ہے.اگر اس وقت کے گذرنے کے بعد بھی بچے کو دودھ پلایا جائے تو اس کے معدہ میں اس قسم کی کمزوری پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ ٹھوس غذا ہضم نہیں کر سکتا.اسے سیّال غذا کی ہی عادت رہتی ہے.ذرا ٹھوس غذا اندر جائے تو اسہال شروع ہو جاتے ہیں.بڑوں کو دیکھ لو جب کوئی بیمار ہو اور دس پندرہ دن دودھ یا چاول استعمال کرتا رہے تو اس کے بعد جب وہ روٹی کھانا شروع کرتا ہے تو ابتدا میں اسے بدہضمی ہو جاتی ہے کیونکہ سیّال غذا استعمال کرنے کی وجہ سے معدہ کمزور ہو جاتا ہے.اسی طرح دودھ بے شک ایک اچھی غذا ہے مگر بچے کے لئے خدا تعالیٰ نے ڈیڑھ دو سال تک ہی اسے غذا بنایا ہے اگر بعد میں بھی دودھ جاری رکھا جائے جیسا کہ ناواجب محبت کرنے والی مائیں بعض دفعہ تین تین چار چار پانچ پانچ بلکہ سات سات سال تک دودھ پلاتی چلی جاتی ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اوّل تو دودھ خراب ہو جاتا ہے اور وہ بچے کو بیمار کر دیتا ہے دوسرے اس کے معدے کو سخت غذائیں ہضم کرنے کی عادت نہیں پڑتی اور اس کا معدہ ہمیشہ کے لئے کمزور ہو جاتا ہے جس طرح بڑی عمر کے آدمی کو اگر ٹھوس غذا نہ ملے تو وہ کمزور ہوجاتا ہے اسی طرح بچے کو جب ٹھوس غذا کی ضرورت ہو اگر دودھ پر ہی رکھا جائے تو وہ بھی کمزور ہو جاتا ہے.مگر بعض عورتوں کو دیکھا گیا ہے وہ کئی کئی سال تک ناواجب محبت کے جوش میں بچے کو دودھ پلاتی جاتی ہیں اور جب پوچھا جائے کہ کیوں پلاتی ہو تو وہ کہہ دیتی ہیں کیا کریں یہ چھوڑتا ہی نہیں.اگر چھڑائیں تو رو پڑتا ہے.نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خود بھی کمزور ہو جاتی ہیں اور بچہ بھی کمزور ہو جاتا ہے.تو فرماتا ہے باقی رب کامل نہیں.کبھی کسی چیز کی ضرورت کا موقع ہو گا تو وہ مہیا نہیں کریں گے.کبھی موقع نہیں ہو گا تو مہیا کر دیں گے مگر خدا تعالیٰ ایسا نہیں اس کی ربوبیت ہر قسم کے نقائص سے منزّہ اور پاک ہے.قرآن مجید کے آخری زمانے میں نازل کئے جانے کی وجہ میں نے تمہید میں یہ بتایا تھا کہ پہلی سورۃ کی آیت اِنَّہٗ لَقَوْلٌ فَصْلٌ سے یہ اعتراض پیدا ہوتا تھا کہ خدا تعالیٰ نے شروع میں ہی کیوں قولِ فصل نازل نہیں کر دیا اس کا جواب اس آیت میں دیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ خدا تعالیٰ ربّ ہے اس لئے وہ ضرورت اور تدریج کو ضرور مدنظر رکھتا ہے.جب ایک ماں جو ناقص طور پر صفتِ ربوبیت کو ظاہر کرنے والی ہے شروع میں ہی اپنے بچے کو روٹی نہیں کھلا دیتی اور صرف دودھ پلاتی ہے پھر ہم غیر مناسب غذا کس طرح دے سکتے تھے.لیکن
Page 34
میں اس کا ذکر کر دیا گیا.یہ نہیں ہوا کہ بدی کی ایجاد سے پہلے الٰہی کلام میں کس بدی کا ذکر کر دیا گیا ہو.اگر ابتدا میں ہی کامل شریعت کے نزول کے ساتھ ہر قسم کی بدیوں کا ذکر کر دیا جاتا تو وہ جرائم جو ہزاروں سال بعد پیدا ہوئے ان کی بنیاد اسی وقت پڑ جاتی اور دنیا اخلاقی اور روحانی اعتبار سے تباہ ہو جاتی.پھر بعض ربوبیتیں ایسی ہوتی ہیں جو خود غرضی کے ماتحت ہوتی ہیں.انسان خوشامدکے لئے یا جھوٹی نیک نامی حاصل کرنے کے لئے دوسرے سے معاملہ کرتا ہے مگر خدا تعالیٰ ایسا نہیں کرتا.یا انسان بعض دفعہ بے موقع اور بےمحل کام کر دیتا ہے مگر خدا کی ربوبیت میں کوئی نقص نہیں پایا جاتا.یہی مضمون ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا ہے اور بتایا ہے کہ تیرے رب کی ربوبیت ایسی نہیں جو اپنے اندر کسی قسم کا نقص رکھتی ہو.پس گو نام کے لحاظ سے صفات الٰہیہ میں دوسروں کو بھی ناقص طور پر اشتراک حاصل ہے مگر حقیقتاً صفات الٰہیہ دوسروں کی صفات سے بالکل مغائر ہیں.جیسے رب ہونے کے لحاظ سے لوگوں کو ایک قسم کا اشتراک حاصل ہے یا رحیم ہونے یا عالم ہونے یا مالک ہونے میں بھی وہ ان ناموں میں مشترک ہوتے ہیں.لیکن یہ اشتراک صرف ظاہر میں ہو گا.حقیقت دونوں کی جداگانہ ہوگی.ناموں میں اشتراک محض اس لئے ہے کہ اس کے بغیر انسان خدا تعالیٰ کی صفات کو سمجھ نہیں سکتا تھا اسی لئے خدا تعالیٰ کی صفت سے ملتا جلتا نام اس کا رکھ دیا ورنہ انسان کی صفت بالکل اور رنگ کی ہے اور خدا تعالیٰ کی صفت اور رنگ کی.یہ طریق صرف تقریب تفہیم کے لئے اختیار کیا گیا ہے ورنہ خدا تعالیٰ کی ربوبیت اور قسم کی ہے اور بندے کی ربوبیت اور قسم کی.خدا کی رحیمیّت اور قسم کی ہے اور بندے کی رحیمیّت اور قسم کی.خدا کی مالکیّت اور قسم کی ہے اور بندے کی مالکیّت اور قسم کی.خدا اور بندے کا اگر بعض صفات کے لحاظ سے ایک قسم کا نام رکھا جاتا ہے تو اس لئے کہ بندہ خدا تعالیٰ کی صفات کو سمجھ سکے.اگر ہم انسان کو بھی مالک کہتے ہیں اور خدا کو بھی مالک کہتے ہیں تو اس کا مفہوم صرف اس قدر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں جو مالکیّت کی صفت پائی جاتی ہے اس سے ایک ناقص تشابہ انسان کو بھی حاصل ہے نہ کہ ویسی ہی صفت انسان کو حاصل ہے.کیونکہ بندے کی صفت ناقص ہوتی ہے اور خدا تعالیٰ کی صفت کامل ہوتی ہے.پس فرمایا سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى تیرا رب جو اعلیٰ ہے یعنی اس کی ربوبیت سب دوسروں سے بلند اور ارفع ہے اس کی تسبیح کر یعنی خدا تعالیٰ کے صفاتی اسماء میں شریک ہونے کی وجہ سے لوگوں کے بعض ناقص افعال کی بناء پر لوگ خدا تعالیٰ کی صفات کے متعلق بھی کئی قسم کے شبہات میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور وہ یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ بندے اور خدا کے کام ایک جیسے ہیں.تُو ان شبہات کا ازالہ کر اور خدا تعالیٰ کی ربوبیت پر جو اعتراضات وارد ہوتے ہیں ان کو دور کر.یہ ایک لطیف اور وسیع مضمون ہے کہ
Page 35
صفات الٰہیہ کے ظاہری اشتراک سے دھوکا نہیں کھانا چاہیے.سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى میں اسم سے مراد خدا تعالیٰ کے سب اسماء دوسرے معنے اس آیت کے یہ ہیں کہ اسم سے مراد ہر اسم یعنی اسماء ہیں اور مراد یہ ہے تیرا رب جو اعلیٰ ہے اس کے نام کی تسبیح کر یعنی سب سے زیادہ احسان تجھ پر تیرے رب کا ہے جس سے بڑھ کر اور کوئی ربوبیت نہیں کر سکتا.جب اس نے تجھ سے وہ سلوک کیا ہے جو اور کسی سے نہیں کیا تو اب تیرابھی فرض ہے کہ جو شخص خدا تعالیٰ کی ذات پر کسی قسم کا اعتراض کرے تو اس کے اعتراض کا ازالہ کر.یہ ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ کا تیرے ساتھ وہ معاملہ رہا ہے جس کی دنیا میں اور کہیں نظیر نہیں ملتی اس لئے تو ہی صحیح طور پر لوگوں کے شکوک کا ازالہ کر سکتا ہے کیونکہ جس نے خدا تعالیٰ کو دیکھا ہو وہی اس کی صفات پر لوگوں کے اعتراضات کو ردّ کر سکتا ہے جس نے اپنی ذات میں خدائی صفات کا مشاہدہ ہی نہ کیا ہو وہ کسی کے اعتراض کا کیا ازالہ کر سکتا ہے.پس فرماتا ہے ربِّ اعلیٰ نے تیری خود ربوبیت کی ہے اور تیرے ساتھ وہ سلوک کیا ہے جو دنیا میں اور کسی سے نہیں کیا اس لئے اب یہ تیرا کام ہے کہ صفاتِ الٰہیہ میں سے ہر صفت پر جو اعتراضات لوگوںکی طرف سے وارد ہوتے ہیں ان کو دور کر اور ان کو بتا کہ خدائی صفات ہر قسم کے نقائص سے منزّہ ہیں.واقعات پر غور کر کے دیکھ لو خدا تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسا سلوک کیا ہے ویسا سلوک دنیا میں اور کسی سے نہیں ہوا.اس لئے خدا تعالیٰ کی صفات کو جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم سمجھ سکتے تھے کوئی اور شخص نہیں سمجھ سکتا تھا.مثلاً خدا تعالیٰ کی مالکیّت کی صفت لے لو.خدا نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم کے لئے جس رنگ میں اپنی مالکیت کا اظہار کیا اس رنگ میں ابوجہل کے لئے نہیں کیا.ابو جہل تو صرف خیالی طور پر سمجھتا تھا کہ چونکہ لوگ کہتے ہیں خدا مالک ہے اس لئے میں بھی سمجھتا ہوں کہ وہ مالک ہے مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو خدا تعالیٰ نے عملًا مالک بن کر دکھا دیا کہ مالک کون ہوتا ہے؟ وہی جس کے قبضہ و اختیار میں تمام چیزیں ہوں اور وہ جس کو چاہے دے اور جس سے چاہے واپس لے لے.خدا تعالیٰ نے بھی عربوں سے حکو مت لے لی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دی.اب بھلا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا خدا تعالیٰ کی اس صفت کو اور کون صحیح طور پرسمجھ سکتا تھا.دوسرے لوگ بھی خدا تعالیٰ کو مالک سمجھتے ہیں مگر اس طرح کہ زید کہتا ہے خدا مالک ہے، بکرکہتا ہے خدا مالک ہے، خالد کہتا ہے خدا مالک ہے مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے خود مالک بن کر دکھا دیا اور اپنی اس صفت کا آپؐپر بلاواسطہ اظہار کیا اس لئے آپؐاس صفت کو جس رنگ میں سمجھ سکتے تھے دوسرے لوگ
Page 36
کہاں سمجھ سکتے تھے.یامثلاً خدا تعالیٰ کی صفت ربوبیت کو ہی لے لو لوگ دنیا میں پیدا ہوتے.ماں باپ کے زیرِ سایہ رہ کر پرورش حاصل کرتے اور اساتذہ سے علوم حاصل کرتے ہیں انہیں یہی نظر آتا ہے کہ ماں باپ نے روٹی کھلائی.ماں باپ نے کپڑے دیئے ماں باپ نے روپے خرچ کئے اور اساتذہ نے ہم کو پڑھا دیا.وہ خدا تعالیٰ کو رب تو کہتے ہیں مگر اس کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی محض سنی سنائی بات ہوتی ہے.وہ حیران ہوتے ہیں کہ ہمارے مولوی تو کہتے ہیں خدا رزق دیتا ہے.خدا روپیہ دیتا ہے.خدا علم دیتا ہے مگر ہمیں تو یہی نظر آتا ہے کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں کھلایا اللہ تعالیٰ نے نہیں کھلایا.ہمارے ماں باپ نے ہمیں پڑھایا اللہ تعالیٰ نے نہیں پڑھایا.لیکن چونکہ لوگ کہتے ہیں کہ اصل رب خدا ہے اس لئے وہ بھی خدا تعالیٰ کو رب کہہ دیتے ہیں ان کے دل اس بات پر یقین نہیں رکھتے اور ان کی آنکھیں خدا تعالیٰ کی اس صفت کو دیکھنے سے قاصر رہتی ہیں مگر فرماتا ہے سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى اور لوگوں کے سامنے تو خدا تعالیٰ اپنی ادنیٰ ربوبیت ظاہر کر رہا تھا مگر تیرے لئے اس نے اپنی اعلیٰ ربوبیت کو ظاہر کیا.یعنی خدا تعالیٰ کی ربوبیت د۲و قسم کی ہوتی ہے ایک ادنیٰ ربوبیت جو لوگوں کے توسط سے ظاہر ہوتی ہے اور ایک اعلیٰ ربوبیت جو توسط کے بغیر ظاہر ہوتی ہے.پس فرماتا ہے تو ان اعتراضات کو دور کر جو ہماری ربوبیت کی صفت پر کئے جاتے ہیں.لوگوں کو ہم نے روٹی کھلائی مگر ان کے ماں باپ کے ذریعہ.لوگوں کو ہم نے علم سکھایا مگر ان کے استادوں کے ذریعہ.لیکن تجھے ہم نے براہِ راست اپنی تربیت میں رکھا.تجھے اپنے پاس سے رزق دیا اور خود علم سکھایا اور اپنی تمام صفات کا بلا واسطہ ظہور تیرے لئے کیا.اب تیرا فرض ہے کہ تو صفاتِ الٰہیہ پر لوگوں کے اعتراضات کو دور کرے.اور ان کے شکوک و شبہات کا ازالہ کرے.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر خدا تعالیٰ کی صفات کا بلاواسطہ ظہور رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جس رنگ میںہر قسم کے علوم سے نوازا اور اپنی صفات کا براہِ راست نمونہ آپؐکو دکھایا اس کا صرف اس بات سے ہی اندازاہ لگایا جا سکتا ہے کہ لوگ تو دنیوی استادوں سے علوم سیکھتے ہیں.مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خود براہِ راست ہر قسم کا علم سکھایا.پھر لوگوں کو علم کے حصول کے لئے بڑی بڑی مشقتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مشقت برداشت نہیں کرنی پڑی.لوگ تورات پڑھنا چاہتے ہیں تو کبھی عبرانی زبان سیکھتے ہیں کبھی یونانی زبان سیکھتے ہیں کبھی پرانے صُحف کا مطالعہ کرتے ہیں اور کئی سال ان کے اسی جدوجہد اور تگ و دومیں صرف ہو جاتے ہیں مگر اس کے باوجود ان کو جو علم حاصل ہوتا ہے وہ ناقص ہوتا ہے اور بسا اوقات بعد کی تحقیق اس کا غلط ہونا ثابت کر دیتی ہے.لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے ہیں.
Page 37
آپؐکو کوئی پتہ نہیں کہ تورات میں کیا کیا احکام تھے.یا بنی اسرائیل کے ساتھ کیا کیا واقعات گذرے.یا موسٰی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کلام کیا تھا.آپؐان سب امور سے بے خبری کی حالت میں رات کو بستر پر سوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپؐپر ان تمام حالات کو منکشف کر دیتا ہے اور پھر وہ حالات ایسے صحیح ثابت ہوتے ہیں کہ آج وہ باتیں تو سچی ثابت ہورہی ہیں جو خدا تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں لیکن وہ باتیں غلط ثابت ہو رہی ہیں جو لوگوں نے بہت بڑی جدّوجہد اور سالہا سال کی محنت کے بعد معلوم کی تھیں اور تاریخی کتابوںمیں درج کی تھیں.اب دیکھ لو اس بلاواسطہ ربوبیت کے نتیجہ میں جس طرح آپؐکہہ سکتے تھے کہ خدا علیم ہے اس طرح اور کون خدا کے علیم ہونے کی شہادت دے سکتا تھا بے شک لوگ بھی خدا تعالیٰ کو علیم تسلیم کرتے ہیں مگر اس لئے نہیںکہ انہوں نے خدا تعالیٰ کے علیم ہونے کا مشاہدہ کیاہوتا ہے بلکہ اس لئے کہ ان کے ماں باپ یا استاد کہتے ہیں کہ خدا علیم ہے لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رات کو بغیر علم کے سوئے اور صبح کو آپؐکا سینہ ہر قسم کے علوم سے بھرا ہوا تھا.آپؐجس طرح خدا تعالیٰ کے علیم ہونے کی صفت کا بے عیب ہونا ظاہر کر سکتے تھے دوسرے لوگ اس طرح کہاں ظاہر کر سکتے تھے.پھر مثلاً رزق کو لے لو.لوگ دیکھتے ہیں کہ انسان خود محنت کرتا، خود روزی کماتا اور خود اپنے اور اپنے بیوی بچوں کے لئے معاش کا سامان مہیا کرتا ہے.ان کے سامنے خدا تعالیٰ کی صفت رزاقیت بغیر توسط کے ظاہر نہیں ہوتی.نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی اس صفت کے متعلق محض سماعی ایمان رکھتے ہیں مشاہدہ کی برکات ان کو حاصل نہیں ہوتیں.وہ بے شک رسمی طور پر اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ رزاق ہے مگر ان کے دل اس صفت کے متعلق ہرقسم کے یقین سے خالی ہوتے ہیں.لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے اپنی اس صفت کو بھی بغیر کسی توسط کے ظاہر کیا اور آپؐکو جب بھی رزق ملا بغیر محنت کے ملا.آپؐجب بچے تھے اللہ تعالیٰ نے آپؐکی غیر معمولی محبت آپؐکے رشتہ داروں کے دلوں میں پیدا کر دی.یہاں تک کہ آپؐکی تربیت کے لئے جو دایہ مقرر ہوئی وہ بھی آپؐسے بے انتہا محبت کرنے والی ثابت ہوئی.چنانچہ تاریخوں میں ذکر آتا ہے کہ حلیمہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دایہ تھیں وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کیا کرتی تھیں اور اس کی وجہ یہ تھی کہ خدا تعالیٰ نے آپؐکو ان کے لئے رزق کا ذریعہ بنا دیا تھا.آپؐکی دایہ کے خاندان کے لوگ سخت غربت کی حالت میں تھے مگر آپؐکے آنے پر خدا تعالیٰ نے ان کی غربت کو دور کر دیا اور اپنے فضل کے دروازے ان کےلئے کھول دئیے اس لئے آپؐسے ان کو بےانتہا محبت ہو گئی.آنحضرتؐکی وجہ سے جو آپؐکی دایہ پر خدا کا فضل ہوا تھا اس وجہ سے وہ یہ چاہتی تھیں کہ زیادہ سے زیادہ عرصہ آنحضرتؐان کے گھر میں رہیں.تا وہ برکات جو آپؐکی وجہ سے ان کے گھر پر نازل ہو رہی تھیں ان سے زیادہ
Page 38
سے زیادہ متمتع ہو سکیں.چنانچہ جب آپؐدو سال کے ہوئے تو آپؐکی دایہ آپؐکی والدہ کے پاس گئیں اور اصرار کرکے انہیں واپس لے آئیں.(السیرۃ النبویۃ لابن ھشام زیر عنوان ولادۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورضاعتہ) مکہ کے لوگوںمیں دستو ر تھا کہ وہ اپنے بچے ارد گرد کے گاؤں میں رہنے والی عورتوں کے سپرد کر دیا کرتے تھے.تاکہ کھلی ہوا میں رہنے کی وجہ سے ان کی صحت اچھی رہے اور زبان بھی صاف رہے.کیونکہ بدوی لوگوں کی زبان شہریوں کی نسبت زیادہ فصیح ہوا کرتی ہے.اور گاؤں کی عورتیں اس لئے شہر کے بچوں کو لے جاتی تھیں کہ ان بچوں کی پرورش کے لئے ان کے ماں باپ کافی رقم ان کو دیتے تھے جس سے ان کا گذارا بھی اچھا ہو جاتا تھا.چنانچہ حلیمہ بھی اسی غرض سے مکہ میں آئی اور اس غرض کے لئے آئی کہ اگر کسی کا بچہ ملے تو اسے اپنے ساتھ لے جائے.مگر وہ کہتی ہیں میں مکہ کے جس گھر میں بھی گئی لوگ میرے پھٹے پرانے کپڑوں اور پریشان بالوں کو دیکھ کر کہتے کہ ہم تجھے اپنا بچہ نہیں دے سکتے کیا ہم نے اپنا بچہ بھوکا مارنا ہے کہ اسے تیرے حوالے کر دیں.اسی حالت میں مَیں سارا دن مکہ میں پھرتی رہی مگر مجھے کوئی بچہ نہ ملا.ادھر یہ واقعہ ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سارا دن اپنا بچہ بعض دوسری عورتوں کو دینے کے لئے اصرار کرتی رہیں مگر کوئی عورت اس بچہ کو لینے کے لئے تیار نہ ہوتی.وہ یہی کہتیں کہ تو ایک غریب عورت ہے ہم اس بچہ کو لے گئیں تو تُو نے ہمیں کیا انعام دینا ہے.گویا مکہ میں ایک عورت کو سارا دن کوئی بچہ نہ ملا اور ایک عورت کو سارا دن اپنے بچہ کے لئے کوئی دایہ نہ ملی.دایہ کو ہر گھر سے اس لئے ردّ کیا گیا کہ وہ ایک غریب عورت ہے اگر بچہ لے گئی تو وہ اس کی پوری طرح پرورش نہ کر سکے گی.اور بچے کو اس لئے ردّ کیا گیا کہ اس کی ماں ایک غریب اور بیوہ عورت تھی وہ پالنے والی کو انعام کیا دے گی.اس لئے سب عورتیں اسے کہتیں کہ ہم تیرے بچہ کو لے گئیں تو ہمیں تجھ سے کسی انعام کی امید نہیں ہو سکتی.حلیمہ کہتی ہیں جب شام ہو گئی اور سورج غروب ہونے لگا تو میں شرمندہ اور حیران ہو گئی اور سوچنے لگی کہ سارا دن گذر گیا اور مجھے کسی نے غربت کی وجہ سے اپنا بچہ نہیں دیا کہ اتنے میں مجھے کسی نے بتایا کہ فلاں گھر میں ایک بچہ ہے جسے ابھی تک کوئی دایہ نہیں ملی.تُو اس گھر میں جا اور اس بچے کو لے لے.حلیمہ کہتی ہیں میں نے سمجھا کہ خالی ہاتھ واپس جانے میں جو شرمندگی ہے اس سے یہ بہتر ہے کہ میں اس بچہ کو ہی اپنے ساتھ لے جاؤں.چنانچہ میں گئی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے آئی.جب میں گھر پہنچی تو ایک عجیب نظارہ نظر آیا.ہماری بکریوں کا دودھ بوجہ قحط سالی کے خشک ہو چکا تھا اور دیر سے ہمارے ہاں کوئی دودھ نہیں تھا لیکن جب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے گھر پہنچی تو ہماری بکریوں کے تھَن دودھ سے بھر گئے.وہ کہتی ہیں میں دل میں تو کڑھتی آئی تھی کہ محض اپنی ناک کے لئے اور
Page 39
سہیلیوں میں شرمندگی سے بچنے کے لئے میں اس بچے کو لائی ہوں ورنہ اس بچے کی ماں مجھے کیا دے سکتی ہے لیکن جب میں نے یہ دیکھا کہ ہماری بکریوں کے تَھن دودھ سے بھر گئے ہیں تو میں نے کہا یہ بچہ تو ہمارے لئے رزق لایا ہے.چنانچہ اس دن سے ان کے دل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بیٹھ گئی اور پھر انہوں نے اپنے بچوں سے بھی زیادہ محبت اور شفقت کے ساتھ آپؐکی پرورش کی.(السیرۃ النبویۃ لابن ھشام زیر عنوان ولادۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورضاعتہ) تو دیکھو وہ لوگ جو دوسروں کے ہاتھ سے روٹی کھاتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کو اپنا رب سمجھتے ہیں مگر اس لئے نہیں کہ انہوں نے اس کی ربوبیت کا کوئی کرشمہ دیکھا ہوتا ہے بلکہ اس لئے کہ لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ رب ہے.مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے خدا تعالیٰ نے اپنی صفتِ ربوبیت کا اس وقت ظہور کیا جب آپؐسمجھتے بھی نہیں تھے کہ رب کیا ہوتا ہے.اور پھر جب آپؐنے ہوش سنبھالا تو اس وقت دایہ نے آپؐکو بتایا کہ ہم نے تجھے نہیں کھلایا بلکہ تیری وجہ سے ہم نے کھایا ہے.اب سوچو کہ رب کے جو معنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ سکتے تھے وہ اور کون سمجھ سکتا تھا.یقیناً اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو وہی صحیح طور پر سمجھ سکتا ہے جو براہِ راست صفت ربوبیت کا نمونہ دیکھے.وہ شخص جو واسطوں کے ذریعہ سے کسی صفت کا مشاہدہ کرتا ہے اس پر بھی اس صفت کا اثر ہوتا ہے.مگر وہ اثر اور یہ اثر آپس میں بہت بڑا فرق رکھتے ہیں.اس کی ایسی ہی مثال ہے جیسے بعض دفعہ ہم کسی غریب کو خود پیسہ دے دیتے ہیں اور بعض دفعہ کسی اور کو پیسہ دے کر کہتے ہیں کہ یہ فلاں غریب کو دے دینا.اب یہ لازمی بات ہے کہ پیسے تو دونوں صورتوں میں غریب کو ہی پہنچیں گے مگر براہِ راست پیسہ دینے سے ہماری جو محبت اس شخص کے دل میں پیدا ہو سکتی ہے وہ مخفی صدقہ دینے سے پیدا نہیں ہو سکتی.بے شک مخفی صدقہ دینے والے کو ثواب زیادہ مل جاتا ہے مگر جسے صدقہ ملتا ہے اس کے دل میں صدقہ دینے والی کی محبت پیدا نہیں ہو سکتی.لیکن اگر کوئی شخص براہِ راست کسی غریب کو صدقہ دیتا ہے تو خواہ ثواب اسے کم حاصل ہو مگر دوسرے شخص کے دل میں محبت کا جوش پیدا ہو جائے گا اور وہ اس کے لئے ضرور دعا کرے گا.اسی طرح جن لوگوں کو خدا تعالیٰ نے ماں باپ کے ہاتھ سے روٹی کھلائی ہے ان کو خدا تعالیٰ کی ربوبیت کا وہ مزہ نہیں آ سکتا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی براہِ راست ربوبیت سے حاصل ہوتا تھا.اسی طرح خدا تعالیٰ کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ زندہ کرنے والا ہے.اس صفت کے متعلق بھی ہرشخص رسمی رنگ میں ایمان رکھتا ہے اور وہ کہہ دیتا ہے کہ ہاں مجھے ایمان ہے اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد لوگوں کو زندہ کرے گا مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے خدا تعالیٰ کی یہ صفت آپؐکی زندگی میں ہی ظاہر ہوئی اور آپؐنے اس کی
Page 40
صفتِ احیاء کا اسی دنیا میں اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیا.آپؐجس قوم میں مبعوث ہوئے اس پر ایسی تباہی اور بربادی آئی ہوئی تھی کہ جس کی نظیر دنیا میں بہت ہی کم پائی جاتی ہے.مگر پھر خدا تعالیٰ نے آپؐکے ذریعہ ہی آپؐکے ہاتھ پر اس مردہ قوم کو زندہ کر دیا اور اسے دنیا کا فاتح اور حکمران بنا دیا.عجیب بات یہ ہے کہ اور بیمار تندرست ہونا چاہتے ہیں مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علاج کے لئے جو بیمار ملا وہ ایسا تھا جو اپنی زندگی کا خواہاں نہیں تھا.بلکہ چاہتا تھا کہ مرجائے اور اس کا وجود دنیا سے مٹ جائے.مگر پھروہی بیمار جو مرنا چاہتا تھا جو زندگی کا ملنا ناممکن سمجھتا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے اچھا ہوا، زندہ ہوا اور اس نے دنیا کے اور ہزاروں لاکھوں لوگوں کو زندہ کر دیا.مکہ کے لوگ جن میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی معمولی تاجر تھے.نہ ان کو حکومت حاصل تھی، نہ ان میں کوئی نظام موجود تھا، نہ انہیں کوئی عزت اور شہرت حاصل تھی.انتہائی کس مپرسی کی حالت میں ایک گوشہ گمنامی میں پڑے ہوئے تھے.مگر دیکھو وہ لوگ آپؐکے ذریعہ سے کس طرح زندہ ہو کر دنیا میں پھیل گئے.جس طرح چیل جھپٹا مار کر اپنے شکار کو قابو میں کر لیتی ہے اسی طرح وہ دیوانہ وار دنیا میں نکلے اور بڑی بڑی حکومتوں کو انہوں نے تَہ وبالا کر دیا.اہلِ عرب کی حیثیت اس قدر معمولی تھی کہ ہمسایہ حکومتوں کے ادنیٰ ادنیٰ تحصیلدار بھی ان کو ڈانٹ ڈپٹ دیا کرتے تھے.مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آنے کے بعد ان کی طاقت کا یہ حال ہو گیا کہ وہ بڑی بڑی حکومتوں کے ساتھ ٹکرانے لگ گئے.قیصر و کسریٰ کی سلطنتیں ان کے مقابلہ میں پاش پاش ہو گئیں.اور بڑے بڑے بادشاہ گردن جھکائے اور ہتھیار ڈالے ان کے سامنے حاضر ہوئے.یہ نمونہ تھا اس احیاء کا جو اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا.اور لوگوں کی یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ دوسروں سے سن کر کہہ دیتے ہیں کہ خدا مردے زندہ کیا کرتا ہے.باپ نے کہہ دیا کہ خدا مُـحْیٖ ہے تو بچے نے بھی مان لیا.استاد نے کہہ دیا کہ خدا مُـحْیٖ ہے تو شاگرد نے بھی تسلیم کر لیا مگر جس شخص نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ خدا مُـحْیٖ ہے جس شخص نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ وہ قوم جو صدیوں سے مردہ چلی آرہی تھی.جو زندہ نہیں ہونا چاہتی تھی وہ زندہ ہو گئی.وہ فاتح اور حکمران ہو گئی.وہ خدا تعالیٰ کی اس صفت کا بے عیب ہونا جس طرح ظاہر کر سکتا ہے کوئی دوسرا کس طرح کر سکتا ہے.اسی طرح خدا تعالیٰ کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ شافی ہے.مگر لوگ اس صفت کی حقیقت سے ناواقف ہوتے ہیں.وہ زبان سے تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شافی ہے مگر انہوں نے اس کی صفتِ شفا کا کوئی عملی نمونہ دیکھا نہیں ہوتا.وہ تو اتنا ہی جانتے ہیں کہ ہم نے ہَڑ کھائی اس لئے پاخانہ آ گیا.ان کا ذہن صرف مادیات میں ہی الجھ کر رہ جاتا ہے اس عظیم الشان ہستی کی طرف ان کا دل متوجہ نہیں
Page 41
ہوتا جو اس تمام کارخانۂ عالم کو چلا رہی ہے.ان کا ذہن ہَڑ کی طرف تو چلا جاتا ہے مگر خدا تعالیٰ کے شافی ہونے کی طرف ان کا ذہن نہیں جاتا.مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ نے اپنی اس صفت کا بھی براہِ راست نمونہ دکھایا.خیبر کی فتح کا سوال پیدا ہوا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیؓ کو بلایا اور لشکرِ اسلامی کا عَلم آپؓکے سپرد کرنا چاہا مگر حضرت علیؓ کی آنکھیں دُکھ رہی تھیں.اور شدّتِ تکلیف کی وجہ سے وہ سوجھی ہوئی تھیں.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیؓ کو اس حالت میں دیکھا تو آپؐنے علیؓ سے فرمایا ادھر آؤ.وہ سامنے آئے تو آپ نے اپنا لعابِ دہن حضرت علیؓ کی آنکھ پر لگایا اور ان کی آنکھیں اسی وقت اچھی ہوگئیں (السیرۃ النبویۃ لابن ہشام زیر عنوان ذکر المسیـر الی خیبـر) آپؐجانتے تھے کہ خدا نے کہا ہے خیبر علیؓ نے فتح کرنا ہے.اور جب کہ خدائی فیصلہ یہ ہے تو اس کی آنکھ بیمار نہیں رہ سکتی.آپؐنے لعاب دہن لگایا اور آنکھ فوراً اچھی ہوگئی.اب جس شخص کے ساتھ یہ معاملہ گذرا ہو وہی بتا سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ شافی ہے دوسرا اگر کچھ کہے گا تو یہی کہ میں نے سنا ہے کہ خدا شافی ہے مگر مجھے اس کی اس صفت کے متعلق کوئی مشاہدہ حاصل نہیں.سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى سے یہ مراد کہ رب کی اعلیٰ شان کو ظاہر کر غرض اللہ تعالیٰ کی تمام صفات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلاواسطہ دیکھیں مگر لوگوں نے ان صفات کو بالواسطہ دیکھا اس لئے لوگ ان عیوب کو دور نہیں کر سکتے تھے جو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کئے جاتے تھے مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ذاتی مشاہدہ کی بنا پر ان عیوب کو بڑی عمدگی اور خوبی کے ساتھ دور کر سکتے تھے اس لئے فرمایا سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے رب کے نام کی تسبیح کر اس لئے کہ تیرے لئے اس کی ربوبیت اعلیٰ ظاہر ہوتی ہے مگر اور لوگوں کے لئے ربوبیت ادنیٰ ظاہر ہوتی ہے اس لئے لوگوں نے اس کی صفات کا نقش نہایت دھندلی صورت میں دیکھا ہے مگر تیرے لئے تو ہم اپنی تمام صفات کے ساتھ ظاہر ہو گئے ہیں اور تو نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ ہم میں کوئی نقص نہیں.اس لئے بنی نوع انسان کی طرف سے جو اعتراضات کئے جاتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی تعلیم میں یہ نقائص ہیں.اس کی صفات میں یہ عیوب ہیں.ان کی پورے زور سے تردید کر.کوئی کہتا ہے بتوں کو خدائی دے دی گئی ہے.کوئی کہتا ہے خدا کا بیٹا ہے.کوئی کہتا ہے فرشتے اس کی بیٹیاں ہیں.کوئی کہتا ہے وہ کلام نہیں کرتا.کوئی کہتا ہے کائناتِ عالم کے چلانے میں صرف اسباب کا دخل ہے خدا تعالیٰ کا ہاتھ اس میں کوئی کام نہیں کر رہا.غرض کئی قسم کے اعتراضات ہیں جو لوگوں کی طرف سے کئے جاتے ہیں.اور وہ اس قسم کے اعتراضات میں اس لحاظ سے معذور بھی سمجھے جا سکتے ہیں کہ انہوں نے ہم کو دیکھا نہیں.ہماری صفات
Page 42
اور جلال اور قدرت کا مشاہدہ انہوں نے نہیں کیا مگر تو نے تو ہم کو دیکھ لیا ہے کیونکہ ہم تیرے لئے ربّ الاعلیٰ ہونے کی صورت میں ظاہر ہوئے ہیں اس لئے اب یہ تیرا ہی حق ہے کہ جو عیوب لوگوں کی طرف سے منسوب کئے جاتے ہیں ان کو دور کر اور خدا تعالیٰ کی عظمت دنیا میں ظاہر کر.ان معنوں کی صورت میں اسم سے مراد سارے اسماء لئے جائیں گے صرف ایک اسم مراد نہیں لیا جائے گا.پھر اسم سے اسماء مراد لینے کی صور ت میں اس طرف بھی اشارہ سمجھا جائے گا کہ خدا تعالیٰ کی شان تو سب سے اعلیٰ ہے لیکن بوجہ اس کے کہ وہ رب ہے ادنیٰ سے اعلیٰ کی طرف لے جاتا ہے.اس قانون کے ماتحت اس نے پہلی کتب میں تشبیہی کلام استعمال کئے تھے لیکن اب ربوبیت اپنے کمال کو پہنچ گئی ہے اور حقیقت پر سے پردہ اٹھانے کا وقت آ گیا ہے اس لئے تو ان تمام غلطیوں کا ازالہ کر جو صفاتِ الٰہیہ کے بارہ میں پہلی کتب سے لگ رہی تھیں.اگر قرآن کریم کا سابق الہامی کتب سے مقابلہ کیا جائے تو فوراً معلوم ہو جائے گا کہ پہلی کتب میں ربّ الاعلیٰ ہونے کا اظہار نہیں کیا گیا.یعنی پہلی کتب کے نزول کے وقت چونکہ انسانی دماغ ابھی اپنے ارتقاء کو نہیں پہنچا تھا اور وہ زیادہ باریک باتوں کو سمجھنے کی استعداد نہیں رکھتا تھا بلکہ ابھی نشوونما حاصل کر رہا تھا اس لئے ان کتب میں تشبیہی کلام کثرت کے ساتھ استعمال کیا گیا تھا کبھی کسی نبی کی بعثت کو خدا کا آنا کہہ دیا جاتا.کبھی اللہ تعالیٰ کو باپ کہہ کر پکارا جاتا.کبھی اس کے پیاروں کو خدا کا بیٹا کہہ دیا جاتا.کیونکہ بغیر ان استعارات اور تشبیہی کلام کے وہ حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے تھے.مگر فرماتا ہے اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے لئے ہم ربّ الاعلیٰ ہونے کی صورت میں ظاہر ہوئے ہیں.یعنی تمام تشبیہات اور استعارات سے منزّہ اور بالا ہو کر ہم نے اپنا وجود تجھ پر ظاہر کیا ہے.اس لئے پہلی کتابوں سے جو اعتراضات پیدا ہوتے ہیں تو ان کو دور کر.پہلی کتابوں کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں کبھی اللہ تعالیٰ کو باپ کہہ دیا جاتا، کبھی اسے ماں کہہ کر پکارا جاتا ،کبھی کسی نبی کو خدا کا بیٹا کہہ دیا جاتا، کبھی کسی نبی کو خدا کا اکلوتا قرار دے دیا جاتا.اس کے یہ معنے نہیں تھے کہ اللہ تعالیٰ کے بھی بیٹے ہیں یا اللہ تعالیٰ بھی باپ اور ماں کی طرح ہے بلکہ صرف اس حقیقت کو ظاہر کرنے کے لئے کہ جس طرح بیٹا باپ میں سے نکلتا ہے اسی طرح نبی خدا تعالیٰ کی طرف سے اس کی صفات کو ظاہر کرنے کے لئے کھڑا ہوتا ہے.یہ تشبیہی کلام استعمال کیا گیا تھا اور دراصل ایسا ہونا ضروری بھی تھا.کیونکہ انسانی دماغ ابھی نشوونما پارہا تھا وہ ارتقائی منازل کو آہستہ آہستہ طے کر رہا تھا اور ابھی وہ اس قابل نہیں ہوا تھا کہ شریعت کے باریک احکام یا الٰہی کلام کی باریک حکمتوں کو سمجھ سکے.مگر اب تیرے لئے ہم ربّ الاعلیٰ ہونے کی صورت میں ظاہر ہوئے ہیں.
Page 43
تشبیہ تب دی جاتی ہے جب کوئی چیز اوپر سے نیچے کی طرف آئے.مگر جب کوئی چیز اونچی چلی جائے تو اس کے لئے تشبیہات و استعارات استعمال کرنے کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے.اسی امر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم تیرے لئے ربّ الاعلیٰ ہونے کی حیثیت میں ظاہر ہوئے ہیں.اس لئے تمام تشبیہات کی تشریحات کر دی گئی ہیں.اور بتا دیا گیا ہے کہ جب خدا تعالیٰ کو باپ کہا جاتا تھا تو اس کے کیا معنے تھے.اورجب کسی نبی کو اس کا بیٹا یا اکلوتا بیٹا کہا جاتا تھا تو اس کے کیا معنے تھے.توحید کیا ہوتی ہے.شرک کن باتوں سے پیدا ہوتا ہے.شرک کی کیا کیا قسمیں ہیں.یہ اور اسی قسم کے تمام مسائل کو ہم نے پوری طرح واضح کر کے رکھ دیا ہے.اس لئے تو جس طرح ان غلطیوں کو دور کر سکتا ہے پہلے لوگ ان غلطیوں کو دور نہیں کر سکتے تھے.کیونکہ پہلے انبیاء کے لئے ہم ربّ الاعلیٰ ہونے کی حیثیت میں ظاہر نہیں ہوئے اس کے یہ معنے نہیں کہ وہ اس وقت ربّ الاعلیٰ نہیں تھا بلکہ اس کے صرف اتنے معنے ہیں کہ ظہورِ ربوبیت اعلیٰ اس وقت نہیں ہوا تھا.لیکن اس وقت ربوبیت اپنے کمال کو پہنچ گئی ہے.اور شریعت کو ہر لحاظ سے کامل کر دیا گیا ہے.اس لئے اس کے ہر حکم کی حکمت اور ہر تعلیم کی خوبی کو واضح کر دیا گیا ہے.اور تیرا فرض ہے کہ تو ان اعتراضات کو دور کرے جو خدا تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات اور اس کی تعلیم وغیرہ کے متعلق کئے جاتے ہیں.اگر اعلیٰ کو اسم کی صفت قرار دیا جائے تو اس کے یہ معنے ہوں گے کہ تیرے رب کا جو اعلیٰ نام ہے اس کی تسبیح کر اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے ادنیٰ نام بھی ہیںبلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی تمام صفات اس وقت اعلیٰ رنگ میں ظاہر ہو رہی ہیں.تیرا کام یہ ہے کہ ہر صفت کا جو اعلیٰ ظہور ہے اسے پیش کر اور ہر صفت پر جو اعتراض پڑتا ہو اسے دور کر تاکہ پہلے تمام اعتراضات مٹ جائیں اور خدا تعالیٰ کا جلال اپنی پوری شان کے ساتھ دنیا پر ظاہر ہو.سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى کے متعلق یہ امر بھی یاد رکھنا چاہیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپؐکے صحابہؓ کا طریق یہ تھا کہ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے جب وہ رکوع میں جاتے توکہا کرتے اَللّٰھُمَّ لَکَ رَکَعْتُ اور جب سجدہ میں جاتے تو کہتے اَللّٰھُمَّ لَکَ سَـجَدْتُّ مگر جب یہ آیت نازل ہوئی کہ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِجْعَلُوْھَا فِی سُـجُوْدِکُمْ.یہ تسبیح سجدہ کے وقت کیا کرو.اور جب یہ آیت نازل ہوئی کہ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ (الـحاقۃ:۵۳)تو آپؐنے فرمایا اِجْعَلُوْھَا فِیْ رُکُوْعِکُمْ یہ تسبیح رکوع کے وقت کیا کرو.(مـسنـد احـمـد بن حنبل بروایت عقبہ بن عامر الـجھنی) چنانچہ یہ جو ہم رکوع میں سُـبْحَانَ رَبِّیَ الْعَظِیْمِ اور سجدہ میں سُـبْحَانَ رَبِّیَ الْاَعْلٰی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اسی حکم کے نتیجہ میں کہتے ہیں کہ
Page 44
فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ اور سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى.گویا خدا تعالیٰ نے بتا دیا کہ رکوع میں کس طرح تسبیح کرنی چاہیے اور سجدہ میں کس طرح تسبیح کرنی چاہیے.ورنہ اس سے پہلے مسلمان رکوع میں اَللّٰھُمَّ لَکَ رَکَعْتُ اور سجدہ میں اَللّٰھُمَّ لَکَ سَـجَدْتُ کہا کرتے تھے.سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى میں اس طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ چونکہ اعلیٰ اور بلند ہستی کا علم حاصل کرنا چھوٹی ہستیوں کے لئے مشکل ہوتا ہے اس لئے خدائی صفات کے متعلق یہ فیصلہ کرنا کہ ان کی کس رنگ میں تجلّی ہوتی ہے.کون کون سی باتیں خدا تعالیٰ کی صفات کے منافی ہیں اور کون کون سی باتیں اس کی صفات کے مطابق ہیں یہ انسان کا کام نہیں اور نہ اس میں یہ قوت پائی جاتی ہے کہ وہ اپنی طرف سے خدا تعالیٰ کی صفات کے متعلق اندازے لگانے شروع کر دے اور سمجھ لے کہ وہ ایسا ہو گا.بلکہ یہ خدا کا کام ہے کہ وہ اپنی وحی کے ذریعہ سے بندوں کو اس قسم کے امور سے آگاہ فرمائے.اس لئے خدا تعالیٰ کی طرف سے وحی کا نازل ہونا ضروری ہے.وہ لوگ جو وحیٔ الٰہی کی ضرورت تسلیم نہیں کرتے وہ بالفاظِ دیگر خدا تعالیٰ کا اپنی عقل سے احاطہ کرنا چاہتے ہیں حالانکہ یہ ناممکن ہے.خدا تعالیٰ کی ہستی اور اس کی صفات کے متعلق انسان کوئی ایک بات بھی اس وقت تک معلوم نہیں کر سکتا جب تک اللہ تعالیٰ اپنی وحی کے ذریعہ سے ان امور سے خود آگاہ نہ فرمائے اس لئے وحی کا ہونا ضروری ہے.بغیر وحیٔ الٰہی کے نہ انسان اللہ تعالیٰ کی صفات کو سمجھ سکتا ہے اور نہ اس کے قرب کے راستوں کو اختیار کر سکتا ہے.پس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہے کہ تو جس پر وحی نازل ہوئی ہے صفاتِ الٰہیہ کو لوگوں پر ظاہر کر وہ خود اپنی عقل سے ان صفات کو نہیں سمجھ سکتے.الَّذِيْ خَلَقَ فَسَوّٰىۙ۰۰۳ (وہ) جس نے (انسان کو) پیدا کیا اور (اسے) بے عیب بنایا.حلّ لُغات.سوّی.سَوَّی الشَّیْءَ تَسْوِیَۃً کے معنے ہوتے ہیں جَعَلَہٗ سَـوِیًّا وَصَنَعَہٗ مُسْتَوِیًّا اس کو درست اور عیبوں سے پاک بنایا.اور سَوّٰی کے معنے یہ بھی ہوتے ہیں کہ عیبوں کو دور کیا.چنانچہ کہتے ہیں سَوَّیْتُ الْمُعْوَجَّ فَـمَا اسْتَوٰی.میں نے ٹیڑھے کو سیدھا کرنا چاہا مگر وہ سیدھا نہ ہوا (اقرب ) گویا سَوّٰی کے معنے یہ بھی ہیں کہ اسے ایسا بنا یا کہ اس میں کوئی عیب نہ تھا اور سَوّٰی کے یہ بھی معنے ہیں کہ اس کو جو کج تھا درست کیا.
Page 45
گویا بے عیب بنانا یا عیب کو دور کر دینا یہ دونوں باتیں تسویہ میں شامل ہیں.پس الَّذِيْ خَلَقَ فَسَوّٰى کے معنے یہ ہوئے کہ جس خدا نے پیدا کیا اور پھر اس کو بے عیب بنایا یا جس خدا نے پیدا کیا اور پھر عیب پیدا ہونے کی صورت میں ان عیوب کو دور کیا.تفسیر.خدا تعالیٰ نے پیدا کیا اور اسے درست اور بے عیب بنایا.اس کے یہ معنے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے انسان کو ایسے رنگ میں پیدا کیا ہے کہ اس کے اندر تمام ضروری طاقتیں موجود ہیں اور ترقی کے مادے اس میں پوری طرح پائے جاتے ہیں گویا وہ سب صفات جو انسانی ترقی کے لئے ضروری تھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لئے مہیا فرما دی ہیں.اسی بنا پر بائیبل میں آتا ہے:.’’خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا.‘‘ (پیدائش باب ۱ آیت ۲۷) سوّٰی کے یہ معنی کہ انسان میں اعتدال اور ترقی کا مادہ پیدا کیا ہے پس سَوّٰی کے معنے یہ ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں اعتدال اور ترقی کا مادہ پیدا کیا ہے.ہر قسم کی قابلیتیں اس میں رکھ دی ہیں اور ہر قسم کی ضروریات اس کے لئے مہیا کر دی ہیں اور یہی بے عیب پیدا کرنے کے معنے ہیں.ورنہ بے عیب پیدا کرنے کے یہ معنے تو نہیں ہو سکتے کہ اس کے اندر خدائی پائی جاتی ہے.اس کے معنے یہی ہیں کہ انسانی پیدائش میں کوئی چیز ایسی نہیں جس کے متعلق یہ کہا جا سکے کہ وہ لغو اور فضول ہے.مثلاً آنکھ ہے، یہ بالکل بےکار ہوتی اگر اس کے مقابل میں سورج کی روشنی پیدا نہ کی جاتی مگر اللہ تعالیٰ کا احسان دیکھو کہ اس نے ایک طرف آنکھ پیدا کی تو دوسری طرف سورج کی روشنی پیدا کر دی تا کہ آنکھ کام کر سکے.اسی طرح تمام جسمِ انسانی کو دیکھ لو ہر چیز کسی نہ کسی غرض کے لئے پیدا کی گئی ہے.اور اس کا ضرور کوئی نہ کوئی فائدہ ہے.صرف د۲و چیزیں انسانی جسم میں ایسی ہیں جن کے متعلق ڈاکٹروں کا یہ خیال تھا کہ ان کی کوئی غرض نہیں یہ یوں ہی پیدا کر دی گئیں ہیں.ایک تو کان کی لَو کے متعلق خیال کیا جاتا تھا کہ یہ کسی خاص غرض کے لئے نہیں ہے.دوسرے مِعَاءٌ اَعْوَرُ یعنی اپنڈکس کے متعلق یہ خیال کیا جاتا تھا کہ جسمِ انسانی میں اس کا کوئی خاص کام نہیں.بعض اور چیزیں بھی تھیں جن کے متعلق پہلے زمانہ میں یہ خیال کیا جاتا تھا کہ وہ بے فائدہ پیدا کی گئی ہیںلیکن آہستہ آہستہ ان کی ضرورت کو اطباء نے ظاہر کر دیا.صرف یہ دو چیزیں رہ گئیں تھیں مگر آج سے چالیس۴۰ پچاس۵۰ سال پہلے مِعَاءٌ اَعْوَرُ کی ضرورت کو بھی ڈاکٹروں نے محسوس کر لیا.چنانچہ فرانس کے ایک ڈاکٹر نے یہ معلوم کرنے کے لئے کہ آیا مِعَاءٌ اَعْوَرُ کا کوئی فائدہ ہے یا نہیں بارہ بندر لئے
Page 47
فائدہ یہ بھی ہے کہ چونکہ اس کے اندر لچک پائی جاتی ہے اس وجہ سے آواز اس کے ذریعہ سے ایک لہر پیدا کر دیتی ہے جس کی وجہ سے آواز زیادہ عمدگی سے سنی جا سکتی ہے.یہ ایک موٹا فائدہ کان کی لَو کا ہے.اور بھی کئی فوائد ہوں گے جو اپنے اپنے وقت ظاہر ہوتے رہیں گے.پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے انسان کو پیدا کیا اور پھر اسے بے عیب بنایا ہے.کوئی چیز ایسی نہیں جس کی کوئی نہ کوئی غرض نہ ہو.ہر چیزاللہ تعالیٰ نے حکمت اور انسانی فائدہ کو مدنظر رکھتے ہوئے پیدا کی ہے.پھر خَلَقَ فَسَوّٰى کے یہ بھی معنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو معتدل القویٰ بنایا ہے اور اس کی قوتوں میں اس نے ہر لحاظ سے اعتدال پیدا کیا ہے.ایک طرف اگر اس نے انسان میں غصہ کی طاقت رکھی ہے تو اس کے بالمقابل اس نے نرمی کی قوت بھی اس میں رکھ دی ہے.اگر ایک طرف اس میں انتقام کی قوت پائی جاتی ہے تو دوسری طرف عفو کی قوت بھی اس میں موجود ہے.اگر ایک طرف اس میں شہوت کا مادہ پایا جاتا ہے تو دوسری طرف عفت کا مادہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھ دیا ہے.یہ دونوں بظاہر متضاد قوتیں مل کر انسان کی اخلاقی اور روحانی ترقی کا موجب ہوتی ہیں.اگر ایک دوسرے کے بالمقابل اس قسم کی متضاد قوتیں انسان میں موجود نہ ہوتیں تو وہ کبھی بااخلاق نہیں کہلا سکتا تھا.جس شخص کے اندر شہوت نہیں وہ کبھی عفیف نہیں کہلا سکتا.جس شخص کے اندر غصہ نہیں وہ معاف کرنے والا نہیں کہلا سکتا.اور جس شخص کے اندر نرمی نہیں وہ غیور نہیں کہلا سکتا.اخلاق کی حکومت اسی شخص پر ہوتی ہے جس میں دونوں قابلیتیں پائی جاتی ہوں.حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام اس کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی نامرد ہو تو اسے یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ بڑا عفیف ہے یا اگر کوئی شخص نابینا ہو تو اس کے متعلق ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کبھی بدنظری نہیں کرتا اس لئے کہ اس کی نظر ہے ہی نہیں.اگر اس کی نظر موجود ہوتی اور پھر وہ بدنظری سے محفوظ رہتا تو یہ بے شک قابلِ تعریف بات تھی.لیکن جب کہ اس کی آنکھیں ہی نہیں تو اسے پاک نظر والا کس طرح کہا جا سکتا ہے.حقیقت یہ ہے کہ جب تک دونوں قسم کی قوتیں انسان میں نہ پائی جائیں اور ان قوتوں میں وہ صحیح توازن قائم نہ کرے اس وقت تک وہ اخلاقی زندگی بسر کرنے والا قرار نہیں دیا جا سکتا.پس خَلَقَ فَسَوّٰى کے ایک معنے یہ بھی ہیں کہ ہم نے انسان کو معتدل القویٰ بنایا ہے اور اس کے دائیں بائیں متضاد قوتیں رکھی ہیں اور اس کے اندر یہ مادہ پیدا کیا ہے کہ وہ ان قوتوں کے درمیان میں اپنے آپ کو اس طرح کھڑا رکھے جس طرح ترازو کے دو پلڑے آپس میں برابر ہوتے ہیں.اگر ایک طرف ہم نے اس میں شہوت کا مادہ رکھا ہے تو دوسری طرف ہم نے عفت کا مادہ بھی اس میں رکھ دیا ہے.ایک طرف پاکیزگی کا مادہ ہم نے پیدا کیا ہے تو
Page 48
دوسری طرف غلاظت بھی اس کے ساتھ لگا دی ہے.ایک طرف چستی بنائی ہے تو دوسری طرف سستی بنا دی ہے.ایک طرف کھانے پینے کے سامان بافراط پیدا کر دیئے ہیں تو دوسری طرف روزہ رکھ دیا ہے یعنی اس میں ایسی قوت رکھ دی ہے کہ وہ ضرورت پر فاقہ کشی کر سکتا ہے.غرض دونوں قسم کے قویٰ انسان میں پیدا کئے گئے ہیں.اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسان میں یہ قابلیت رکھی ہے کہ وہ ان قویٰ کا صحیح استعمال کر کے بااخلاق، نیک اور روحانی آدمی بن جائے.پس فرماتا ہے ایک طرف تو تمام ضروری طاقتیں ہم نے انسان میں رکھ دی ہیں اور دوسری طرف اس میں ترقی کا مادہ پیدا کر دیا ہے تاکہ وہ ان قوتوں سے کام لے کر اخلاقی اور مذہبی رنگ میں ترقی کر سکے.خَلَقَ فَسَوّٰى کے ایک یہ بھی معنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور پھر جب جب اس میں خرابی پیدا ہوئی اللہ تعالیٰ نے اس کی درستی کے سامان کئے اور اس کی کجی کو دور کیا.تَسْویہ کے ایک معنے جیسا کہ اوپر بتایا جا چکا ہے عیب پیدا ہونے پر اس عیب کو دور کرنے کے ہوتے ہیں.پس خَلَقَ فَسَوّٰى کے ایک معنے یہ بھی ہیں کہ اس نے انسان کو پیدا کیا اور جب کبھی اس میں خرابی پیدا ہوئی اللہ تعالیٰ نے اس کو دور کیا.جو خدا اپنے بندوں کا اس قدر خیال رکھتا ہے اور ہر خرابی پر اس کو دور کرنے کے سامان مہیا کرتا ہے اس کی طرف یہ عیب کبھی منسوب نہیں کیا جاسکتا کہ خرابی تو پیدا ہو مگر وہ اس کو دور کرنے کے سامان مہیا نہ کرے.پہلی سورۃ میں بیان شدہ قولِ فصل کے متعلق ایک شک کا ازالہ دیکھو! اللہ تعالیٰ نے یہاں کس لطافت سے اس اعتراض کا جواب دے دیا ہے جو پہلی سورۃ سے پیدا ہوتا تھا.میں بتا چکا ہوں کہ قولِ فصل کے متعلق یہ اعتراض پیدا ہوتا تھا کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم کے ذریعہ قولِ فصل آ چکا اور لوگوں کی راہنمائی کے لئے آپؐایک کامل تعلیم لے آئے تو اس کے بعد کسی اور موعود کی کیا ضرورت ہے.اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتا ہے.تم اللہ تعالیٰ کی صفات کی طرف دیکھوکہ اس کے جسم پر جو بیماریاں حملہ کرتی ہیں ان کے علاج کے سامان بھی اس نے دنیا میں پیداکئے ہیں.جب بھی انسان بیمار ہوا اور اس میں کسی قسم کی خرابی پیدا ہوئی اللہ تعالیٰ نے اس کے تَسْوِیَہ کے سامان پیدا کر دئیے.جب جسمانی بیماری پیدا ہوئی تو جسم کی صحت کے سامان پیدا کئے.جب روحانی بیماری پیدا ہوئی تو روحانی بیماریوں کے علاج پیدا کر دیئے.پس جب اللہ تعالیٰ ہمیشہ ایسا کرتا چلا آیا ہے تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ آئندہ کجی تو پیدا ہو مگر وہ اس کو دور کرنے کے سامان پیدا نہ کرے اگر یہ ثابت ہو جائے کہ کسی وقت کجی تو پیدا ہوئی مگر خدا نے اس کو دور نہیں کیا تو اس سے خدا کا ناقص ہونا ثابت ہو گا اور اس کی صفات پر اعتراض واقع ہو گا.اگر دنیا میں خرابی پیدا ہو سکتی ہے تو بہرحال اس کو دور کرنا ضروری ہو گا کیونکہ
Page 49
یہ خدا کی سنّت ہے کہ انسان جب بھی خرابی میں مبتلا ہوتا ہے وہ اس کی ہدایت کے سامان پیدا کر دیتا ہے.اگر تم کہو کہ خدا کو قولِ فصل کے بعد اس قسم کی خرابیاں دور نہیں کرنی چاہئیں تو دوسرے الفاظ میں تم خدا تعالیٰ کو موردِ الزام بنانا چاہتے ہو.پس تمہارا یہ خیال کہ قولِ فصل کے بعد کسی وحی کی ضرورت نہیں ایک غلط اور بے بنیاد خیال ہے.اگر نقص پیدا ہو تو اس کو دور کرنے کا سامان اللہ تعالیٰ ضرور کرتا ہے.ورنہ اس پر اعتراض عائد ہوتا ہے کہ خرابی کا اس نے کیوں علاج نہ کیا.پس فرماتا ہے آج تک یہی ہوتا چلا آیا ہے کہ جب بھی دنیا میں خرابی پیدا ہوئی ہم نے اس کو دور کرنے کے سامان پیدا کر دئیے.ہاں یہ ضرور ہے کہ علاج خرابی کے مطابق ہونا چاہیے.مثلًا اگر کوئی شخص ایسا ہے جو معدہ کی خرابی کی وجہ سے روٹی نہیں کھاتا تو اس کا ایسا علاج ہونا چاہیے جس کے نتیجہ میں وہ روٹی کھا سکے.یہ علاج نہیں ہو گا کہ اس پر کمبل اوڑھا دیا جائے.اگر انسانوں میں عملی خرابی پیدا ہو جائے تو اس وقت صحیح علاج یہ ہو گا کہ ان کی عملی اصلاح کی جائے.یہ علاج نہیں ہوگا کہ نئی شریعت نازل کر دی جائے.لیکن اگر شریعت میں خرابی پیدا ہو جائے تو پھر صحیح علاج یہ ہو گا کہ شریعت کی اصلاح کر دی جائے.بہرحال جیسا مرض ہو گا ویسا ہی علاج ہو گا.اگر کتاب بگڑ جائے تو اس کا علاج ہو گا اور اگر لوگ بگڑ جائیں تو ان کا علاج ہو گا.اگر انسان تو درست ہوں مگر قانون ناقص ہو تو اس وقت قانون کو درست کیا جائے گا اور اگر قانون تو درست ہو مگر لوگوں میں خرابی پیدا ہو جائے تو لوگوں کو درست کیا جائے گا پس خَلَقَ فَسَوّٰى کہہ کر اللہ تعالیٰ نے اس اعتراض کا جواب دے دیا جو اِنَّہٗ لَقَوْلٌ فَصْلٌ کے نتیجہ میں پیدا ہوتا تھا اور بتا دیا کہ انسان میں جب بھی خرابی پیدا ہوئی اللہ تعالیٰ اس کو دور کرتا چلا آیا ہے.اسی طرح آئندہ بھی جو خرابی پیدا ہو گی وہ اس کو ضرور دور کرے گا.وَ الَّذِيْ قَدَّرَ فَهَدٰى ۪ۙ۰۰۴ اور جس نے (اس کی طاقتوں کا) اندازہ کیا اور (ان کے مطابق) اسے ہدایت دی.حلّ لُغات.قَدَّرَ.قَدَّرَہٗ عَلَی الشَّیْءِ کے معنے ہوتے ہیں جَعَلَہٗ قَادِرًا اس کو قادر بنا دیا.اور قَدَّرَ فُلَانٌ کے معنے ہوتے ہیں رَوَّیَ وَفَکَّرَفِیْ تَسْوِیَۃِ اَمْرِہٖ اس نے کسی معاملہ میں غور کیا اور سوچا کہ اسے کس طرح سر انجام دے.قَدَّرَ الشَّیْءَ بِالشَّیْءِ کے معنے ہوتے ہیں قَاسَہٗ بِہٖ وَجَعَلَہٗ عَلٰی مِقْدَارِہٖ اس نے ایک چیز کو دوسری پر قیاس کیا اور اس کے مطابق اسے بنایا(اقرب ) اس آیت میں قَدَّرَ کے تینوں معنے ہو سکتے ہیں.یہ بھی کہ
Page 50
قَدَّرَہٗ عَلَی الشَّیْءِ یعنی قَدَّرَ الْاِنْسَانَ عَلَی الْھُدٰی.اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہدایت پر قادر بنایا یعنی اسے اس قابل بنایا ہے کہ وہ ہدایت پائے اور ترقی کرے.دوسرے معنوں کے لحاظ سے وَ الَّذِيْ قَدَّرَ فَهَدٰى کا یہ مفہوم ہو گا کہ جس نے انسان کی حالت کا ہمیشہ اندازہ لگایا.کیونکہ قَدَّرَ فُلَانٌ کے معنے ہوتے ہیں رَوَّیَ وَفَکَّرَ فِیْ تَسْوِیَۃِ اَمْرِہٖ.پس قَدَّرَفَھَدٰی کے معنے یہ ہوئے کہ جب کبھی خرابی پیدا ہوئی اللہ تعالیٰ نے اس کو دور کرنے کی تجویز کی.اور اس کا خرابی کو دور کرنے کی تجویز کرنا سرسری نہ تھا بلکہ ہمیشہ اس نے اندازہ لگایا کہ خرابی کس قسم کی ہے کتنی بیماری ہے اور کس قدر علاج سے وہ دور ہو سکتی ہے.درحقیقت علاج میں اسی وقت کامیابی ہوتی ہے جب مرض کے مطابق علاج کیا جائے.یہ کبھی نہیں ہو گا کہ ایک شخص کو معمولی ملیریا بخار ہو تو ڈاکٹر اسے روزانہ ساٹھ گرین کونین کھلانا شروع کر دے.لیکن ایک دوسرا شخص جسے شدید ملیریا ہو اسے ڈاکٹر بعض دفعہ اتنی کونین کھلاتا ہے کہ اس کے کان بہرے ہو جاتے ہیں.اب اگر کوئی شخص کہے کہ فلاں شخص کو کونین زیادہ کیوں دی گئی اور فلاں کو کم کیوں تو یہ اس کی نادانی ہو گی.کیونکہ علاج مرض کے مطابق ہوتا ہے.اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی ہمیشہ خرابی کے مطابق اصلاح کے سامان پیدا فرماتا ہے.اور قَدَّرَ فَهَدٰى میں اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مرض کے متعلق پہلے اندازہ لگایا کہ کیا مرض ہے.وہ شدید ہے یا خفیف کتنے علاج سے وہ اچھی ہو سکتی ہے.اور پھر اس اندازہ کے مطابق علاج نازل کیا.قَدَّرَ کے ایک یہ معنے بھی تھے کہ قَاسَہٗ بِہٖ وَجَعَلَہٗ عَلٰی مِقْدَارِہٖ اس نے ایک چیز کو دوسری چیز پر قیاس کیا اور اس کے مطابق اسے بنایا.اس لحاظ سے آیت کے معنے یہ ہوں گے کہ انسان کی مرض اور اس کے علاج کا موازنہ کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کی اصلاح اور درستی کے سامان مہیا کئے.پہلے معنے تو یہ تھے کہ جس قسم کی مرض تھی اسی قسم کا علاج نازل کیا اور دوسرے معنے یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مرض کا اندازہ کیا اور پھر جتنی مرض تھی اتنا علاج بھیج دیا.تفسیر.الَّذِيْ قَدَّرَ فَهَدٰى کا تعلق پہلی آیت سے یہ آیت اپنے دونوں معنوں کے لحاظ سے پہلی آیت کے ساتھ نہایت گہرا تعلق رکھتی ہے اور اسی مضمون کا تسلسل اس میں پایا جاتا ہے جو الَّذِيْ خَلَقَ فَسَوّٰى میں بیان کیا گیا تھا.خَلَقَ فَسَوّٰى کے دو معنے کئے گئے تھے.ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو معتدل القویٰ اور ترقی کرنے والا بنایا.دوسرے یہ کہ جب بھی اس میں کوئی خرابی پیدا ہوئی اللہ تعالیٰ نے اس کو دور کیا.ان دونوں معنوں کے لحاظ سے قَدَّرَ فَهَدٰى کے بھی دو معنے ہوں گے.پہلے معنوں کے مقابل پر یہ کہ چونکہ انسان میں ترقی کی استعداد رکھی گئی تھی اور اسے کامل القویٰ بنایا گیا تھا.خدا تعالیٰ نے اس کی طاقتوں کا اندازہ کر کے اس کے
Page 51
متواتر ترقی کرتے چلے جانے کے ذرائع مہیا کئے.دوسرے معنے الَّذِيْ خَلَقَ فَسَوّٰى کے یہ تھے کہ جب کبھی اس میں خرابی پیدا ہوئی اور وہ کج ہوا اللہ تعالیٰ نے اس کی ضرورت کے مطابق اس کی اصلاح کے سامان کئے اور اس کی کجی کو دور کر دیا.ان معنوں کے لحاظ سے وَالَّذِيْ قَدَّرَ فَهَدٰى کے یہ معنے ہوں گے کہ جب بھی وہ کج ہوا اس کی ضرورت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ہدایت بھجوا دی اور اس طرح اس کی اصلاح کی.اگر ضرورت کے مطابق ہدایت نہ ہوتی یا کم ہوتی تو وہ گمراہ ہو جاتا اور اگر ضرورت سے بڑھ جاتی تب بھی اس کی قوتیں ٹوٹ جاتیں اور وہ حیران رہ جاتا پس اصلاح کا اس نے صحیح طریق اختیار کیا اور اس قدر جو ضروری تھا نازل کیا.گویا جیسی جیسی مرض تھی اور جتنی جتنی کجی پائی جاتی تھی اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے علاج نازل کیا اس کی تفصیل پہلے بیان ہو چکی ہے کہ اگر ضرورت سے زائد تعلیم دی جاتی تو وہ بنی نوع انسان کو ہلاک کرنے والی ثابت ہوتی.چنانچہ اس کی مثال دیتے ہوئے بتایا جا چکا ہے کہ پہلے آدمؑ کے وقت بھی سب بدیوں کے ارتکاب کا نہ موقع تھا نہ انسانی ذہن میں وہ آئی تھیں مگر ان کا ذکر اس وقت کر دیا جاتا تو گناہ پیدا ہوتا نہ کہ اصلاح.پس بدی کے ایجاد ہونے سے پہلے اس کا علاج کرنا درست نہ تھا اسی لئے کامل کتاب اس وقت آئی جب سب بدیاں اور بداخلاقیاں شیطانی لوگوں نے ایجاد کر لیں.دوسرے ارتقائے ذہنی جب تک نہ ہو اس وقت تک اعلیٰ تعلیمات کا سمجھنا بھی آسان نہیں ہوتا.پس ضروری تھا کہ ارتقائے ذہنی تک وقتی کامل کتاب دی جاتی نہ کہ کُلّی کامل.غرض چونکہ انسان کامل القویٰ پیدا کیا گیا تھا اس لئے کامل القویٰ ہونے کے لحاظ سے ایک وقت پھر اسے کامل طور پر کامل تعلیم ملنی چاہیے تھی اور بوجہ ارتقاء کا مادہ اپنے اندر رکھنے کے اسے ایک وقت تک صرف وقتی کامل تعلیمات ملنی چاہیے تھیں.اگر کامل تعلیم نہ ملتی تو اس کی طاقتوں کا پورا جواب نہ ملتا اور اگر وقتی کامل تعلیم نہ ملتی تو ارتقاء کی منازل طے نہ ہو سکتیں اور انسان بوجھ تلے دب کر کامل ہونے سے پہلے ہی مُرجھا جاتا.پس جس خدا نے اسے پیدا کیا اور کامل بنایا اور ساتھ ہی نقائص و امراض کا شکار بھی بنایا تا کہ وہ اپنے عمل اور قوت سے کام لے کر انعام کا مستحق ہو اس کے لئے ضروری تھا کہ وہ ان دونوں باتوں کا لحاظ رکھتا اور ہدایت کا لچک دار انتظام کرتا.چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا.اس نے انسان کو پیدا کیا اور جب بھی اس میں اعوجاج پیدا ہوتا رہا اس کے مطابق وہ اصلاح کے سامان مہیا کرتا رہا.غرض پہلی آیت کے جو د۲و معنے کئے گئے تھے ان کے لحاظ سے اس آیت کے بھی د۲و معنے ہیں.ایک یہ کہ اس نے انسان کی استعدادِ کمال کو ضائع نہیں ہونے دیا بلکہ ہمیشہ اس کے بڑھنے کے ذرائع مہیا کئے.دوسرے یہ کہ مرض پیدا ہونے پر اس مرض کے مطابق علاج نازل کیا.ایک معنوں کے لحاظ سے ترقی کی
Page 52
طرف اشارہ ہے اور دوسرے معنوں کے لحاظ سے ازالۂ مرض کی طرف اشارہ ہے.اس امر کا ثبوت کہ جو معنے میں نے کئے ہیں وہی صحیح ہیں اس سے بھی ملتا ہے کہ یہاں خَلَقَ فَسَوّٰى کے بعد قَدَّرَ فَهَدٰى کا ذکر کیا گیا ہے.اگر یہ معنے درست نہ ہوتے تو خَلَقَ سے قَدَّرَ کو پہلے رکھنا چاہیے تھا.کیونکہ اندازہ پہلے ہوتا ہے اور عمل بعد میں.سو چونکہ خَلَقَ کا ذکر پہلے ہو چکا ہے اس کے بعد خَلَقَ کا اندازہ لگانے کے معنے ہی کوئی نہیں بنتے.جسمانی یا روحانی قوتوں کا اندازہ تو خَلَقَ سے پہلے ہونا چاہیے تھا نہ کہ بعد میں.پیدائش کے بعد جو اندازہ لگایا جائے وہ تو قوتوں کے موقع اور محل پر استعمال کا اندازہ ہی ہو سکتا ہے.یعنی انسان جس وقت جس قدر قویٰ کا اظہار بالفعل کر سکتا تھا اس کا اندازہ کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کے مطابق ہدایت نازل کر دی یا جس قدر بدی کا اظہار کرنے کی اس میں قابلیت پیدا ہوئی اس کا علاج اس نے کیا.جب بدیاں پوری طرح ظاہر ہو گئیں اور نیکیوں کے کامل طور پر ظاہر کرنے کی قابلیت اس میں پیدا ہو گئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے کامل تعلیم بھجوا دی.وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہاں تقدیر پیدائش کا ذکر ہے انہیں غور کرنا چاہیے کہ تقدیر پیدائش خلق سے پہلے ہوتی ہے کہ بعد میں.اگر ایک شخص د۲و چھٹانک کی روٹی پکانا چاہے تو وہ آٹا گوندھتے وقت ہی یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ میں نے د۲و چھٹانک کی روٹی پکانی ہے.یہ نہیں ہوتا کہ وہ روٹی پکا کر فیصلہ کرے کہ میں نے دو چھٹانک کی روٹی پکانی ہے یا ڈیڑھ چھٹانک کی.اس قسم کا اندازہ ہمیشہ پہلے ہوتا ہے نہ کے بعد میں.اسی طرح اگر یہاں تقدیر سے مراد تقدیرِ پیدائش ہوتی تو خلق سے پہلے اس کا ذکر ہونا چاہیے تھا مگر اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا بلکہ خَلَقَ فَسَوّٰى کے بعد یہ فرمایا کہ قَدَّرَ فَهَدٰى پس یہ تقدیر وہ نہیں جو پیدائش سے پہلے ہوتی ہے بلکہ اس تقدیر سے دوسری قسم کی تقدیر مراد ہے.ایک تقدیر قوتوں کی ہوتی ہے اور ایک تقدیر اظہارِ قوت کی ہوتی ہے.قوۃ کی تقدیر خواہ وہ روحانیات سے تعلق رکھتی ہو یا جسمانیات سے ہمیشہ خلق سے پہلے ہوتی ہے لیکن اظہارِ قوۃ کے متعلق تقدیر خلق کے بعد ہر وقت ہو سکتی ہے.پس اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اظہار قویٰ کے متعلق اپنی تقدیر کا ہی ذکر کیا ہے.اور بتایا ہے کہ انسان جس وقت جس قدر قویٰ کا بالفعل اظہار کر سکتا تھا اس کا اندازہ کر کے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے یہی حکمت ہے جس کے ماتحت ایک وقت تو صرف وقتی کامل تعلیمات دی گئیں اور دوسرے وقت اسے کُلّی کامل تعلیم دی گئی.وقتی کامل تعلیم اس وقت دی گئی جب انسان ابھی قوتوں کا پورا اظہار بالفعل نہیں کر سکتا تھا اور ارتقائی منازل کو طے کر رہا تھا یا ابھی ہر قسم کی بدیوں کا پورا اظہار نہیں ہوا تھا.اور کُلّی کامل تعلیم اس وقت دی گئی جب ایک طرف بدیاں پورے طور پر ظاہر ہو گئیں اور دوسری طرف نیکیوں کے پورے طور پر ظاہر کرنے کی قابلیت انسان میں پیدا ہو گئی.
Page 53
اس آیت کے ایک اور معنے بھی ہیں اور وہ یہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے انسان کو معتدل القویٰ اور نقائص سے پاک بنایا ہے.مگر اس کے ساتھ ہی اس نے انسان کے لئے کئی قسم کی حد بندیاں بھی قائم کر دی ہیں.یہ نہیں کہ وہ ان قوتوں کو بے تحاشا استعمال کرنا شروع کر دے.مثلاً اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ پانی پی سکتا ہے خواہ زید کا ہو، بکر کا ہو، عمرو کا ہو، خالد کا ہو، مگر اللہ تعالیٰ نے ایک حد بندی قائم کر دی کہ اپنا پانی پیو دوسرے کا پانی اس کی اجازت کے بغیر نہ پیو.ہمارے ہاں چونکہ پانی کثر ت کے ساتھ ہوتا ہے اس لئے لوگ شائد پانی کی مـثال کو پورے طور پر نہ سمجھ سکیں لیکن عرب کے رہنے والے اس مثال کو خوب سمجھ سکتے ہیں.کیونکہ وہاں دس دس بارہ بارہ میل سے مشکیزوں میں پانی بھر کر آتا ہے.اس لئے وہاں پانی کو جو قیمت حاصل ہے ہمارے ملک میں نہیں.یا مثلاً اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ گوشت کھاؤ.مگر ساتھ ہی احکام نازل کر دیئے کہ خنزیر کا گوشت نہ کھاؤ.مردے کا گوشت نہ کھاؤ.جس جانور کو ذبح نہ کیا گیا ہو اس کا گوشت نہ کھاؤ.گویا کئی قسم کی حد بندیوں میں انسان کو جکڑ دیا گیا.یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ جو چاہے کرے یا جو چاہے استعمال کرے.پھر ایک تقدیر حالات کی ہوتی ہے.یوں تو انسان جو چاہے کر سکتا ہے مگر خدا تعالیٰ نے انسان کو ایسے حالات میں پیدا کیا ہے کہ وہ جو چاہے کر نہیں سکتا.ہر ایک شخص اگر لاکھ روپیہ دینا چاہے تو وہ دے سکتا ہے مگر ہر شخص کے پاس اس قدر روپیہ ہوتا ہی نہیں کہ وہ اپنی خواہش کو پورا کر سکے.خیالی طور پر تو ہر شخص لاکھ بلکہ کروڑ روپیہ بھی دے سکتا ہے مگر جہاں تک عملی طور پر لاکھ یا کروڑ روپیہ دینے کا سوال ہے ہر شخص اتنا روپیہ نہیں دے سکتا.اسی مضمون کے مطابق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہرانسان کے اردگرد ہم نے ایک حدبندی قائم کر دی ہے جس میں سے وہ باہر نہیں نکل سکتا.یہی وہ حد بندی ہے جسے ماحول کہتے ہیں.گویا قَدَّرَ فَهَدٰى سے اللہ تعالیٰ نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ انسان اپنے ماحول کے مطابق چلتا ہے اس نے صرف قویٰ ہی پیدا نہیں کئے بلکہ ان قویٰ کے ظہور کے لئے ایک ماحول بھی پیدا کیا ہے.اس ماحول کو دیکھو اس کے مطابق ہی قویٰ ظاہر ہو سکتے ہیں.پس اللہ تعالیٰ نے جب بھی ہدایت نازل کی ہے ماحول کو مدنظر رکھا ہے.یہ ماحول مادی بھی ہوتا ہے اور دینی بھی.مادی ماحول تو حیوان اور انسان سب کے لئے ہے مگر دینی ماحول یعنی شریعت صرف انسان کے لئے ہے اور پھر شریعت بھی مادی ماحول کے مطابق ہوتی ہے.کبھی کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا حکم ہے، کبھی بیٹھ کر اور کبھی لیٹ کر.یہ سب ماحول کا لحاظ ہے.پس ماحول اگر کامل تعلیم کو چاہے گا تو کامل تعلیم آئے گی اور اگر ماحول کامل تعلیم کو نہ چاہے گا تو کامل تعلیم نہ آئے گی.اس کی وجہ سے اعتراض کرنا قانونِ قدرت پر اعتراض کرنا ہے.اگر ماں بچہ کو کباب نہیں کھلاتی بلکہ دودھ پلاتی ہے تو ربّ الاعلیٰ
Page 54
سے یہ کب امید کی جا سکتی ہے کہ وہ بے محل تعلیم کا نزول کرے.قَدَّرَ فَهَدٰى میں اللہ تعالیٰ نے یہی مضمون بیان کیا ہے کہ کامل تعلیم وہی ہو گی جو ماحول کے مطابق ہو.اگر نماز کے متعلق صرف یہی حکم دیا جاتا کہ ہر شخص کو کھڑے ہوکر پڑھنی چاہیے تو ایک بیمار جو کھڑا نہ ہو سکتا وہ کیا کرتا.اس لئے اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی اجازت دے دی کہ اگر کوئی بیمار ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھ لے.اگر بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر نماز پڑھ لے.گویا ماحول کو مدنظر رکھ کر اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی ہے یہ نہیں ہوا کہ اس نے انسان کے مادی ماحول کو نظر انداز کر دیا ہو.پس کامل تعلیم وہی ہوسکتی ہے جو قَدَّرَ فَهَدٰى کے مطابق ہو.مثلاً اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم تو دے دیا مگر ساتھ ہی کہہ دیا کہ یہ حکم ہرشخص کے لئے نہیں بلکہ ان لوگوں کے لئے ہے جن کے پاس اتنا روپیہ ہو.اگر یہ استثنیٰ نہ کیا جاتا تو لاکھوں لوگ اس تعلیم پر عمل نہ کر سکتے اور گناہ گار بن جاتے.لیکن باقی مذاہب کی تعلیم میں اس ماحول کو مدنظر نہیں رکھا گیا.مثلاً آریہ سماج کی یہ تعلیم ہے کہ مردہ جلانے کے لئے صندل، گھی، زعفران اور کئی قسم کی چیزیں اکٹھی کرنی چاہئیں.چنانچہ پنڈت دیانند صاحب ’’ستیارتھ پرکاش‘‘ میں لکھتے ہیں:.’’جسم کے وزن کے برابر گھی لینا چاہیے اور فی سیر گھی میں ایک رتی کستوری اور ایک ماشہ کیسر ڈالنا چاہیے.کم از کم آدھ من صندل ڈالے زیادہ چاہے جس قدر ہو.اگر، تگر، کافور وغیرہ اور پلاش (ڈھاک) وغیرہ کی لکڑیاں ویدی میں جمانی چاہئیں.اور اس پر مردہ رکھ کر چاروں طرف ویدی کے اوپر منہ کی طرف سے ایک ایک بالشت تک بھر کر (مردہ کو) گھی وغیرہ کی آہوتی دے کر جلانا چاہیے.‘‘ (ستیارتھ پرکاش باب ۱۳ صفحہ ۶۴۲) میں نے ایک دفعہ اندازہ لگایا تو یہ چیزیں جن کو مردہ جلانے کے لئے ضروری قرار دیا گیا تھا قریبًا چھ سو روپیہ کی بن گئیں.حالانکہ کئی آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ اپنے گھر کی تمام چیزوں کو بیچ ڈالیں تب بھی وہ چھ سو روپیہ اکٹھا نہیں کر سکتے.اور کئی لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا کوئی مکان ہی نہیں ہوتا وہ کسی کی ڈیوڑھی پر دربان کے طور پر بیٹھے رہتے ہیںنہ ان کی کوئی زمین ہوتی ہے اور نہ جائیداد.وہ لوگ اتنا گھی، صندل، کستوری اور زعفران کہاں سے لا سکتے ہیں.یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ آریہ سماج کی یہ تعلیم قَدَّرَ فَهَدٰى کے مطابق نہیں.وہ انسانی ماحول کو نظر انداز کر دیتی ہے حالانکہ ہر انسان اپنے ماحول کے مطابق ہی چل سکتا ہے.ماحول سے باہر نکل کر عمل کرنا اس کے لئے ناممکن ہوتا ہے.پس فرماتا ہے ہم نے انسان کو ماحول والا بنایا ہے اور اس کے اردگرد کئی قسم کی دیواریں کھڑی کی ہوئی ہیں.پس ہم نے جو تعلیم دی ہے اس میں ان تمام حدبندیوں کو مدنظر رکھ لیا گیا ہے.اگر یوں کہا جاتا کہ ہر انسان دس روپیہ چندہ دے تو لاکھوں لوگ کافر ہو جاتے.کیونکہ ان کے پاس اتنا روپیہ ہی نہ ہوتا
Page 57
طے کرتے کرتے اس مقام تک پہنچ گیا کہ قولِ فصل کا نازل ہونا ضروری ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا کہ اب انسان میں اس کو برداشت کرنے کی استعداد پیدا ہوگئی ہے تو اس نے قولِ فـصل نازل کر دیا پہلے لوگوں کے لئے قولِ فصل کا نازل کرنا ظلم تھا اور بعد میں آنے والوں کے لئے قولِ فصل کو روک لینا ظلم تھا اس لئے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کیا درست کیا.اس کے کسی فعل پر اعتراض کرنا نادانی اور حماقت کا ارتکاب کرنا ہے.غرض اِنَّہٗ لَقَوْلٌ فَصْلٌ پر جو اعتراضات پیدا ہوتے تھے ان کا جواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس سورۃ میں دیا گیا ہے اور الَّذِيْ خَلَقَ فَسَوّٰى اور وَ الَّذِيْ قَدَّرَ فَهَدٰى میں یہ بتایا گیا ہے کہ الٰہی سنّت یہی ہے کہ بگاڑ ہوتا ہے اور وہ اس کی اصلاح کرتا ہے اور الٰہی قانون سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس نے انسان کو معتدل قویٰ عطا فرمائے ہیں.جب اس نے انسان کو معتدل قویٰ عطا فرمائے ہیں تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اس کی طرف سے ایسی تعلیم نہ آئے جو معتدل ہو یعنی ہر قسم کی قوتوں کا اس میں جواب ہو.جب تک ایسا نہ ہو اس وقت تک شریعت کامل نہیں کہلا سکتی.پس ضروری تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی شریعت آتی جو ہر قسم کی فطرت کا اپنے اندر جواب رکھتی.پھر یہ بھی ضروری تھا کہ جب بھی بنی نوع انسان کے اندر بگاڑ کے سامان پیدا ہوتے اس کی طرف سے اصلاح کے سامان پیدا کر دیئے جاتے.ایک طرف انسان میں بگاڑ کی قوت کا موجود ہونا اس بات کو چاہتا ہے کہ متعدد بار ہدایتیں آئیں اور دوسری طرف اس کا انسان کو معتدل القویٰ اور کامل القویٰ بنانا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ کسی نہ کسی وقت ایسی تعلیم بھی آئے جو اپنی ذات میں کامل ہواور انسانی فطرت کے تمام جذبات کو اس میں ملحوظ رکھا گیا ہو.یہ دونوں معانی الَّذِيْ خَلَقَ فَسَوّٰى میں بیان کئے گئے تھے.اور پھر انہی معانی کی تشریح وَ الَّذِيْ قَدَّرَ فَهَدٰى میں کر دی گئی کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ انسان کی طاقتوں کا اندازہ لگاتا اور پھر اس اندازہ کے مطابق ہدایت نازل کرتا ہے.میںبتا چکا ہوں کہ یہاں پیدائشی طاقتیں یا بالقوہ خاصیتیں مراد نہیں اس لئے کہ وہ پیدائش سے پہلے بنائی جاتی ہیں اور یہاں خَلَقَ کے بعد قَدَّرَ کا ذکر ہے.پس یہاں جس تقدیر کا ذکر ہے اس سے مراد انسانی قویٰ کا بالفعل ظہور ہے.یعنی جس جس رنگ میں انسانی طاقتیں ظہور کرتی گئیں اسی رنگ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت آتی گئی.پس قَدَّرَ کے یہ معنے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اندازہ لگایا کہ انسان میں بالقوہ کتنی بڑھنے کی گنجائش رکھی گئی تھی.یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ خلق پہلے ہو اور یہ خاصیتیں بعد میں پیدا کی جائیں.ہم جب ایک انجن بنانے لگتے ہیں تو اس کے بنانے سے پہلے یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ اس نے اتنے وزن کو کھینچنا ہے اور جب ہم یہ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اس انجن نے اتنا وزن کھینچنا ہے تو اس کے بعد اتنی طاقت کا انجن بنا دیتے ہیں.اچھا صنّاع وہی ہوتا ہے
Page 58
جو انجن بنانے سے پہلے اس کی طاقت کا اندازہ کرے اور اس کے مطابق انجن بنائے.جب وہ انجن بنا لے گا تو فوراً کہہ دے گا کہ یہ انجن اتنا وزن کھینچ سکتا ہے.لیکن اگر کوئی اناڑی انجن بنانے لگے تو وہ بے شک اندازہ نہیں لگا سکے گا اور جب انجن بن جائے گا تو کہہ دے گا دیکھ لو یہ کتنا وزن کھینچ سکتا ہے.جتنا وزن کھینچ لے اتنی ہی اس کی طاقت سمجھ لیں.بہرحال تجربہ کار کسی چیز کے بنانے سے پہلے اس کے متعلق اندازہ لگایا کرتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ بعد میں اندازہ لگائے یا مثلاً ایک تجربہ کار مستری چارپائی بنانا چاہتا ہے تو وہ چارپائی بنانے سے پہلے یہ اندازہ لگائے گا کہ مثلًا میں جس شخص کے لئے چارپائی بنانے لگا ہوں سات فٹ کا ہے میں ساڑھے سات فٹ چارپائی بناؤں.کچھ چارپائی سرہانے کی طرف چلی جائے گی اور کچھ پائنتی کی طرف اور اس طرح سات فٹ کے آدمی کے لئے یہ پوری ہو جائے گی.لیکن اگر کوئی اناڑی چارپائی بنائے گا تو وہ اس قسم کا اندازہ نہیں کرے گا جیسی چارپائی بھی بن جائے گی بنا کر دے دے گا خواہ وہ بڑی ہو یا چھوٹی.اگر چھوٹی بنی تو کہہ دے گا یہ تو خراب ہو گئی ہے اب اور چارپائی بنوا لو.بہرحال یہ صنّاع کا طریق نہیں ہوتا کہ وہ بنانے کے بعد کسی چیز کے متعلق اندازہ کرے لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے خَلَقَ فَسَوّٰى کو پہلے رکھا ہے اور قَدَّرَ فَهَدٰى کو بعد میں رکھا ہے.اس میں اسی طرف اشارہ ہے کہ یہاں ان بالقوہ خاصیتوں کا ذکر نہیں کیا گیا جو انسان میں پیدا کی گئی تھیں بلکہ اس کی بالفعل طاقتوں کے ظہور کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ جس جس وقت انسان کا جتنا نشوونما ہو چکا ہوتا ہے اور جس حد تک وہ اپنے جذبات کو خدائی قانون کے مطابق صحیح طور پر لا سکتا ہے اتنی تعلیم ہم اس کے لئے نازل کر دیتے ہیںیا جتنی خرابیاں پیدا ہوں ان کا علاج کر دیتے ہیں.چنانچہ موسٰی کی کتاب موسوی لوگوں کےلئے کامل تھی.عیسٰیؑ کی تعلیمات عیسوی لوگوں کے لئے کامل تھیں.لیکن اُمّت محمدیہ کے لئے وہ تعلیمات کامل نہیں تھیں کیونکہ اس وقت دنیا اور زیادہ ترقی کر چکی تھی اور ضروری تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وقتی کامل تعلیم کی بجائے کُلّی کامل تعلیم نازل ہوتی.اب اس کی مثال اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ دنیا کی عام پیدائش سے دیتا ہے اور لوگوں کو بتاتا ہے کہ صرف روحانی عالم میں ہی نہیں بلکہ اس مادی دنیا میں بھی ہمارا یہی قانون جاری ہے.وَ الَّذِيْۤ اَخْرَجَ الْمَرْعٰىۙ۰۰۵ فَجَعَلَهٗ غُثَآءً اَحْوٰىؕ۰۰۶ اور جس نے (زمین سے) چارہ نکالا.پھر اسے سیاہ کوڑا کرکٹ بنا دیا.حلّ لغاُت.مَرْعٰی.مَرْعٰی اس گھاس پھونس کو کہتے ہیں جس کو جانور کھاتا ہے.اور مَرْعٰی چراگاہ کو
Page 59
بھی کہتے ہیں (اقرب ) اس آیت میں مَرْعٰی سے مراد گھاس پھونس ہے چراگاہ مراد نہیں.غُثَآءً.غُثَآءً.یہ لفظ غُثَاءٌ اور غُثَّاءٌ دونوں طرح بولا جاتا ہے اور اس کے معنے ردّی چیز کے ہوتے ہیں.ہر قسم کی چیز جو ردّی ہو جائے اس کے متعلق کہتے ہیں وہ غُثَاء ہو گئی اور غُثَاءٌ کے معنے جھاگ کے بھی ہوتے ہیں اور غُثَاءٌ کے معنے ہلاک ہونے والی چیز کے بھی ہوتے ہیں اور غُثَاءٌ درخت کے ان پتوں کو بھی کہتے ہیں جو گر کر سڑ جاتے ہیں.اور جب بارش کا پانی یا سیلاب آتا ہے تو باغوں، میدانوں اور گلیوں میں سے ان سڑے ہوئے پتوں کو پانی اٹھا لیتا ہے اس وقت جھاگ میں مل کر ان گلے سڑے پتوں کے جو باریک باریک ذرّات نکلتے ہیں ان کو بھی غُثَاءٌ یا غُثَّاءٌ کہتے ہیں.(اقرب) اَحْوٰى.اَحْوٰى.یہ لفظ حَوِیَ سے نکلا ہے.حَوِیَ الشَّیْءُ کے معنے ہوتے ہیں کَانَ بِہٖ حُوَّۃٌ اس میں حُوّہ پایا جاتا ہے (اقرب) اور حُوَّۃٌ کے معنے ہوتے ہیں ایسی سیاہی جو سبزی کی طرف مائل ہو.یا ایسی سرخی جو سیاہی کی طرف مائل ہو (اقرب).پس اَحْوٰىکے معنے ہوئے ایسی سیاہ رنگ والی چیز جس میں کچھ سبزی کی جھلک پائی جاتی ہو.یا ایسی سرخ رنگ والی چیز جس میں کچھ سیاہی کی جھلک پائی جاتی ہو.چونکہ اَحْوٰى کے اصل معنے ایسی سیاہ رنگ والی چیز کے ہیں جس میں سبزی کی جھلک پائی جاتی ہو اس لئے اَحْوٰى کا لفظ عربی زبان میں دو طرح استعمال ہوتا ہے.اس چیز کو بھی اَحْوٰى کہتے ہیں جو ایسی شدید سبز ہو کہ اس میں سیاہی کی جھلک پیدا ہوگئی ہو جیسے اعلیٰ درجہ کی روئیدگی ہو تو اس کی سبزی سیاہی مائل ہو جاتی ہے.اس قسم کی روئیدگی نہایت اعلیٰ درجہ کی ہوتی ہے.اور اسی کے متعلق سرسبز وشاداب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے لیکن اس کے بالمقابل اَحْوٰى کا استعمال ایسی چیزوں کے متعلق بھی کیا جاتا ہے جن میں گل سڑ کر سیاہی پیدا ہو جاتی ہے.گویا وہ سڑی گلی چیزیں جو گھاس پھونس کی قسم میںسے ہوتی ہیں اور جو پہلے تو سبز ہوتی ہیں لیکن پانی کے ساتھ مل کر ان میں سڑانڈ پیدا ہوجاتی ہے اور پھر وہ اپنا اصل رنگ چھوڑ کر سیاہ ہو جاتی ہیں ان کو بھی اَحْوٰى کہتے ہیں.تفسیر.قولِ فصل کے متعلق پیدا شدہ سوال کے جواب کے متعلق مزید وضاحت اس آیت میں اللہ تعالیٰ اسی اعتراض کو ردّ کرتا ہے جو قولِ فصل کے متعلق پیدا ہوتا تھا.فرماتا ہے وَالَّذِيْۤ اَخْرَجَ الْمَرْعٰى وہ خدا ہی ہے جس نے چارہ کو پیدا کیا ہے اور چارہ ایک محدود اور تھوڑے زمانہ سے تعلق رکھنے والی چیز ہوتی ہے.بعض گھاس ایسے ہیں جو پندرہ بیس دن رہتے ہیں.بعض سبزیاں ایسی ہیں جو مہینہ دو مہینے رہتی ہیں اور بعض ایسی ہیں جو چار پانچ مہینے رہتی ہیں مگر اس عرصہ کے بعد وہ سڑ گل جاتی ہیں اور خدا ان کو غُثَآءً اَحْوٰى کر دیتا ہے یعنی
Page 60
اس کو سڑی گلی چیز کر دیتا ہے اور وہ اَحْوٰى ہو جاتی ہے.یعنی نہ صرف یہ کہ وہ سڑی ہوئی ہوتی ہے بلکہ گل سڑکر سیاہی مائل ہو جاتی ہے.بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک چیز سڑ تو جاتی ہے مگر اپنا رنگ نہیں چھوڑتی.لیکن کبھی اس میں اتنی سڑانڈ پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اپنا رنگ بھی چھوڑ دیتی ہے.اگر صرف غُثَآءً کا لفظ استعمال کیا جاتا تو اس کے معنے یہ ہوتے کہ وہ بے کار اور گندی چیز ہو جاتی.مگر غُثَآءً کے ساتھ خدا تعالیٰ نے اَحْوٰى کا لفظ بھی بڑھا دیا یہ بتانے کے لئے کہ وہ اتنی گندی اور خراب ہو جاتی ہے کہ اپنا رنگ بھی چھوڑ دیتی ہے.جب دنیا میں خدا تعالیٰ کی پیدا کردہ بعض اشیاء اتنی ناقص اور خراب ہو جاتی ہیں تو تمہارا یہ خیال کر لینا کہ اگر خدا تعالیٰ نے تعلیم دینی ہوتی تو قولِ فصل ہی دیتا ایسی تعلیم کیوں دیتا جو بدل جائے.اور ایک زمانہ کے بعد خراب ہو جائے کس طرح درست ہو سکتا ہے.تم غور کرو اور سوچو کہ چارہ خدا نے پیدا کیا ہے یا کسی اور نے.سبزیاں جو تم استعمال کرتے ہو ان کو خدا نے پیدا کیا ہے یا کسی اور نے.پھر کیا تم نہیں دیکھتے کہ یہی گھاس اور یہی سبزیاں کچھ عرصہ کے بعد اس طرح گل سڑ جاتی ہیں کہ ان میں بدبُو پیدا ہو جاتی ہے.کئی قسم کی گیسیں ان میں سے اٹھنے لگتی ہیںاور مختلف قسم کی بیماریوں کا وہ موجب بن جاتی ہیں.جب یہ سبزیاں اچھی حالت میں ہوتی ہیں تو اس وقت انہیں جانور کھاتے ہیں.انسان استعمال کرتے ہیں.ان کے جسم ان سے نشوونما حاصل کرتے ہیں.ان کے دماغ ان سے طاقت حاصل کرتے ہیں اور وہ ان سبزیوں سے کئی قسم کے فوائد حاصل کرتے ہیں.مگر پھر یہی سبزیاں ایک دن سڑ گل کر مختلف قسم کی بیماریوں اور ملک کی صحت کو برباد کرنے کا موجب بن جاتی ہیں.اگر خدا تعالیٰ نے سبزیاں ترکاریاں پیدا کی ہیں جو سڑتی گلتی اور خراب ہوکر نفع کی بجائے نقصان کا موجب بنتی ہیں اور اس سے خدا تعالیٰ کی خدائی میں کوئی نقص واقع نہیں ہوتا.اگر تم یہ نہیں کہتے کہ یہ چیزیں خدا تعالیٰ نے پیدا نہیں کیں بلکہ کسی اور نے کی ہیں.بلکہ تم کہتے ہو یہ بھی خدا تعالیٰ کی قدرت ہے اور وہ بھی خدا تعالیٰ کی قدرت ہے لمبے فوائد رکھنے والی اشیاء کی پیدائش بھی خدا تعالیٰ کی قدرت کا نتیجہ ہے.اور وہ سبزیاں جو چند دنوں کے بعد ہی سڑ گل جاتی ہیں ان کی پیدائش بھی خدا تعالیٰ کی قدرت کا نتیجہ ہے تو روحانی زندگی میں تمہیں کیوں اعتراض پیدا ہوتا ہے اور کیوں تم اس حقیقت کو نہیں سمجھتے کہ بعض چیزیں عارضی زندگی رکھنے والی ہوتی ہیں اور بعض مستقل.کوئی تعلیم تھوڑے زمانہ کے لئے ہوتی ہے اور کوئی تعلیم لمبے عرصہ کے لئے.خدا تعالیٰ کی مخلوق میں اس کا ثبوت موجود ہے کہ جہاں اس نے بعض چھوٹی چھوٹی چیزیں مثلاً ترکاریاں وغیرہ پیدا کی ہیں جو چند دنوں کے بعد ہی گل سڑ جاتی ہیں وہاں اس نے ایسے درخت بھی پیدا کئے ہیں جو سینکڑوں سال کی زندگی رکھتے ہیں.اور بعض اشیاء تو ایسی ہیں کہ جب تک نسل انسانی رہے گی اس وقت تک وہ چیزیں بھی قائم رہیں گی.
Page 61
مثلاً سورج اور چاند اور پہاڑ اور زمین اور کانیں وغیرہ.یہ مستقل وجود رکھنے والی چیزیں ہیں.غرض دونوں قسم کی مخلوق دنیا میں پائی جاتی ہے.وہ مخلوق بھی پائی جاتی ہے جو کچھ دن فائدہ پہنچا کر ختم ہو جاتی ہے اور وہ مخلوق بھی پائی جاتی ہے جو ہمارے نقطۂ نگاہ سے ہمیشہ ہمیش چلتی چلی جاتی ہے.گو خدا تعالیٰ کے نقطۂ نگاہ سے وہ چیزیں بھی فانی ہیں مثلاً سورج ہے اس کے متعلق خدا ہی جانتا ہے کہ کب پیدا ہوا.کوئی انسانی نسل نہیں کہہ سکتی کہ اس نے سورج کو پیدا ہوتے دیکھا ہے.اسی طرح ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ یہ کب فنا ہو گا.اور نہ ہماری آئندہ نسلیں جان سکتی ہیں کہ یہ کب فنا ہو گا کیونکہ نسل انسانی پہلے فنا ہو گی اور سورج بعد میں.اور اگر بالفرض دونوں کی تباہی ایک ہی وقت ہو تب بھی جاننا کس نے ہے کہ سورج تباہ ہو گیا.نسلِ انسانی بھی ختم ہو جائے گی اور سورج بھی ختم ہو جائے گا.بہرحال کوئی ایسا زمانہ نسلِ انسانی پر نہیں آسکتا جب سورج تباہ ہو جائے اور لوگ یہ کہیں کہ ہمارے باپ دادا سورج کو دیکھتے تھے مگر ہم نہیں دیکھ سکتے کیونکہ وہ فنا ہو چکا ہے.جس طرح ہم سور ج کو دیکھتے چلے آئے ہیں اسی طرح ہماری آئندہ نسلیں بھی اس کو دیکھتی چلی جائیں گی اور کوئی ایسا زمانہ نہیں آئے گا جب انسانی نسل کی موجودگی میں سورج تباہ ہو جائے اور اس کا وجود مٹ جائے.ا سی طرح چاند اور ستارے اور زمین بھی ان اشیاء میںسے ہیں جن کو خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک لمبی زندگی دی گئی ہے.پہاڑ بھی اصولاً انہی چیزوں میں شامل ہیں گو پہاڑوں میں چھوٹی موٹی تبدیلیاں زلازل کے نتیجہ میں ہوتی رہتی ہیں مگر بہرحال پہاڑ بھی انسانی پیدائش سے پہلے موجود تھے اور آخر تک موجود رہیں گے.غرض دونوں قسم کی اشیاء خدا تعالیٰ کی پیدائش میں نظر آتی ہیں اور کوئی شخص ان پر اعتراض نہیں کرتا بلکہ کہتا ہے کہ یہ بھی خدا کی قدرت کا ثبوت ہے اور وہ بھی خدا کی قدرت کا ثبوت ہے.دنیا میں ہزاروں ہزار ایسی چیزیں ہیں جن میں سے کوئی د۲و دن کی زندگی پاتی ہے کوئی دس دن کی.کوئی چھ مہینہ کی اور کوئی صرف گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ کی.برسات کے موسم میں پَردار چیونٹیاں پیدا ہوتی ہیں جو گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ کے بعد ہی فنا ہو جاتی ہیں.ہمارے ملک میں مثل مشہور ہے کہ چیونٹی کو بھی پَرلگے.یہ خاص قسم کی چیونٹیاں برسات میں پیدا ہوتی اور تھوڑی دیر کے بعد ہی فنا ہوجاتی ہیں.ایک دو گھنٹہ کے بعد گھر میں دیکھو تو ان کے ڈھیروں ڈھیر اور سیروں سیر پَر پڑے ہوئے ملیں گے.یہ بھی خدا تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے جو صرف ڈیڑھ گھنٹہ زندگی پاتی ہے مگر کوئی شخص اس کو دیکھ کر خدا کی خدائی پر اعتراض نہیں کرتا.وہ یہ نہیں کہتا کہ سورج کو تو خدا تعالیٰ نے لاکھوں سال سے پیدا کیا ہوا ہے اور یہ چیونٹیاں گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ میں ہی ہلاک ہو جاتی ہیں.بلکہ وہ کہتا ہے یہ چیز بھی خدا کی قدرت کا ثبوت ہے اور وہ چیز بھی خدا کی
Page 62
قدرت کا ثبوت ہے پس یہ کہنا کہ وہ خدائی تعلیم کس طرح ہو گئی جو ایک وقت کے بعد منسوخ ہو گئی اگر خدائی تعلیم ہوتی تو کبھی منسوخ نہ ہوتی بالکل احمقانہ بات ہے.زیادہ تر ہندؤوں میں یہ خیال پایا جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ اگر اپنا کلام نازل کرے تو پھر اسے کبھی منسوخ نہیں ہونا چاہیے.اگر کوئی کلام منسوخ ہو جاتا ہے تو اس کے معنے یہ ہیں کہ وہ کلام خدا کی طرف سے نازل نہیں ہوا تھا.مگر ان کا یہ خیال قطعی طور پر غلط اور بے بنیاد ہے.قانون قدرت پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں قسم کی چیزیں پیدا کی ہیں وہ بھی جو لمبی زندگی رکھتی ہیں اور وہ بھی جو عارضی زندگی رکھتی ہیں.کوئی چیز ایسی ہے جو چند منٹوں میں فنا ہو جاتی ہے.کوئی چیز ایسی ہے جو چند گھنٹوں کی زندگی حاصل کر کے فنا ہو جاتی ہے.کوئی چیز ایسی ہے جو چند مہینوں کے بعد فنا ہو جاتی ہے.کوئی چیز ایسی ہے جو چندسالوں کے بعد فنا ہو جاتی ہے اور کوئی چیز ایسی ہے کہ جب سے انسان آیا اسے دیکھتا چلا آیا اور جب تک رہے گا اسے دیکھتا چلا جائے گا.جن لوگوں نے اَحْوٰى کے معنے نہایت سرسبز و شاداب کے کئے ہیں (تفسیر روح المعانی زیر آیت فَجَعَلَهٗ غُثَآءً اَحْوٰى) ان کو یہاں مشکل پیش آئی ہے.کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَجَعَلَهٗ غُثَآءً اور غُثَاءٌ ردّی اور ٹوٹی ہوئی چیز کو کہتے ہیں.اور ردّی چیز کے متعلق یہ کہنا کہ وہ سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے درست نہیں.اس مشکل کا حل انہوں نے اس طرح کیا ہے کہ اَحْوٰى کو انہوں نے مَرْعٰی کا حال بنا دیا ہے اور فَجَعَلَهٗ غُثَآءً کو جملہ معترضہ قرار دیا ہے.گویا ان کے نزدیک اَحْوٰى مَرْعٰی کے ساتھ لگتا ہے اور معنے یہ ہیں کہ جس خدا نے چارے کو نہایت سرسبز وشاداب بنایا ہے وہی خدا اس چارہ کو کچھ عرصہ کے بعد غُثَآءً بنا دیتا ہے.یعنی باوجود اس کی سرسبزی وشادابی کے اس پر وہ زمانہ بھی آجاتا ہے جب وہ گل سڑ جاتا ہے.اسی طرح سابق تعلیمات صرف وقتی ضرورت کو پورا کرتی تھیں مگر ایک وقت کے بعد سڑ جاتی تھیں آخر وہ وقت آ گیا کہ بنی نوع انسان کو مستقل شریعت دی جائے.سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسٰۤىۙ۰۰۷ ہم (اے مسلمان) تجھے (اس طرح) پڑھائیں گے کہ اس کے نتیجہ میں تو بھولے گا نہیں.حلّ لُغات.تَنْسٰی.تَنْسٰی.نَسِیَ سے مضارع مخاطب کا صیغہ ہے اور نَسِیَ الشَّیْءَ نَسْیًا وَنِسْیَانًا وَنَسَایَۃً وَنَسْوَۃً کے معنے ہوتے ہیں ضِدُّ حَفِظَہٗ یعنی عربی زبان میں نسیان حفظ کے مقابل کا لفظ ہے.
Page 63
قَالَ الرَّاغِبُ: اَلنِّسْیَانُ تَرْکُ الْاِنْسَانِ ضَبْطَ مَااسْتُوْدِعَ.امام راغب کہتے ہیں نسیان کے ایک معنے یہ ہیں کہ جس چیز کا خیال رکھنا انسان کے سپرد تھا اس نے اس کا خیال ترک کر دیا.اِمَّا لِضُعْفِ قَلْبِہٖ.یا تو حافظہ کی خرابی کی وجہ سے یعنی وہ بھول گیا.اَوْ عَنْ قَصْدٍ حَتّٰی یَنْحَذِ فَ عَنِ الْقَلْبِ ذِکْرُہٗ.اور یا جان بوجھ کر وہ اس کا خیال اپنے ذہن میں نہیں آنے دیتا.یعنی وہ چیز اسے بھولی تو نہیں مگر اس پر عمل کرنا اس نے چھوڑ رکھا ہے اور اس کے ساتھ اس کا تعلق کم ہو گیا ہے.وَعَلَیْہِ ’’وَلَاتَنْسَوُا الْفَضْلَ بَیْنَکُمْ‘‘ اَیْ لَا تَقْصِدُوا التَّرْکَ وَالْاِھْمَالَ.وہ کہتے ہیں لَاتَنْسَوُا الْفَضْلَ بَیْنَکُمْ کے بھی یہی معنے ہیں کہ تم ایک دوسرے پر احسان کرنا چھوڑا نہ کرو.یہ مطلب نہیںکہ تم بھولا نہ کرو.(اقرب) گویا لغتاً ترک عمل کے لئے بھی نسیان کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے.پس فَلَا تَنْسٰی کے د۲و معنے ہوئے ایک یہ کہ تم اسے بھولو گے نہیں اور دوسرے یہ کہ تم اسے چھوڑو گے نہیں.یعنی اس پر عمل کرنا ترک نہیں کرو گے.تفسیر.یہ بات تو اوپر کی آیات میں بیان ہو چکی ہے کہ انبیاءِ سابقین کے زمانہ میں صرف وقتی اور عارضی تعلیمات کا آنا اور قولِ فصل کا نازل نہ ہونا خلاف سنّت نہیں.قولِ فصل اسی وقت آ سکتا تھا جب دنیا اس کی برداشت کر سکتی اور زمانہ کو اس کی ضرورت ہوتی.چونکہ قولِ فصل کی ضرورت نزول قرآن کے وقت میں ہوئی اس لئے اس کا نزول اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب ہوا ہے پہلے نہیں ہوا.مگر اس پر د۲و اعتراض اور پڑتے تھے.ایک یہ کہ ہم یہ کیوں کر مان لیں کہ یہ کلام قولِ فـصل ہے.مان لیا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے مگر عارضی اور زمانی اور وقتی چیزیں بھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی رہی ہیں.پس ہم یہ کیوں نہ سمجھ لیں کہ قرآن کریم بھی انہی وقتی تعلیمات میں سے ہے.آخر تمہارے نزدیک تورات فنا ہو گئی یا نہیں.انجیل دنیا سے مٹ گئی یا نہیں.یا ویدوں کا زمانہ تمہارے نزدیک ختم ہو گیا یا نہیں.یاژند اور اوستا منسوخ ہو گئیں یا نہیں.اگر تم ان کتب کے متعلق یہ تسلیم کرتے ہو کہ یہ مٹ گئیں تو اسی طرح ہم کیوں نہ یہ سمجھ لیں کہ اسی قانون کے ماتحت قرآن کریم بھی مٹ سکتا ہے.محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم کے زمانہ میں تو اس کی ضرورت تسلیم کی جا سکتی ہے.مگر ہم کیوں نہ یہ سمجھ لیں کہ اس زمانہ کے گذرنے کے بعد کسی اور وقت یہ کلام اسی طرح منسوخ ہو جائے گا جس طرح سابق الہامی کتب منسوخ ہوئیں.اگر کہو کہ یہ کامل کتاب ہے منسوخ نہیں ہو گی تو تمہارا یہ جواب صحیح نہیں اس لئے کہ موسٰی کی کتاب بھی تو اپنے زمانہ کے لئے کامل تھی.محض تمہارا یہ کہہ دینا کہ اس زمانہ کے لوگوں کے لئے قرآن کریم کامل الہامی کتاب ہے یہ ثابت نہیں کرتا کہ آئندہ بھی یہ کتاب قابلِ عمل رہے گی.اس سے یہ تو ثابت ہو سکتا ہے کہ موجودہ زمانہ
Page 64
کے لئے قرآن کریم کامل الہامی کتاب ہے مگر یہ اس بات کی کوئی دلیل نہیں کہ آئندہ کبھی بھی قرآن کریم کے علاوہ کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہو گی یا اس کی تعلیم کبھی فنا نہیں ہو گی.بلکہ ہو سکتا ہے کہ کسی اور زمانہ میں یہ کتاب مٹ جائے اور اس کی جگہ کوئی اور کتاب آ جائے.دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ کامل کتاب ہے اور ویسی ہی خوبیاں اپنے اندر رکھتی ہے جیسی تم بیان کرتے ہو اور کہتے ہو کہ اس کے بعد اب کوئی اور کتاب نازل نہیں ہو سکتی تو پھر قرآن کریم یہ کیوں کہتا ہے کہ ایک اور موعود آئے گا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں کہتے ہیں کہ میرے بعد ایک اور مامور آئے گا؟ پس یہ د۲و سوال ابھی قابلِ جواب باقی تھے.اوّل یہ کہ ہم کیونکر مان لیں کہ قرآن کریم آخر تک نہ بگڑے گا.اور دوسرے یہ کہ اگر یہ کامل الہامی کتاب ہے تو اس کے بعد کسی موعود کی خبر کیوں دی گئی ہے.ان دونوں سوالات کا ضمنی جواب خَلَقَ فَسَوّٰى اور قَدَّرَ فَهَدٰى میں آ چکا ہے مگر وہ ضمنی جواب تھا.تفصیلی جواب جو مخصوص جواب کہلا تا ہے وہ ابھی نہیں آیا.اب اللہ ان دونوں سوالات کا جواب دیتا ہے.پہلا سوال یہ تھا کہ ہم یہ کیونکر مان لیں کہ قرآن کریم قولِ فصل ہے ہم کیوں نہ یہ کہیں کہ ایک زمانہ کے بعد یہ بھی بدل جائے گا.اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتا ہے.سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسٰۤى.الٰہی قانون یہ ہے کہ جن قانونوں نے بدلنا ہوتا ہے وہ ساتھ کے ساتھ مٹتے چلے جاتے ہیں انسان کو دیکھو اس نے چونکہ مرنا ہوتا ہے اور اس کی جگہ کسی اور قائم مقام نے آنا ہوتا ہے اس لئے ایک عمر کے بعد وہ بوڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ضعف و اضمحلال کے آثار اس میں پیدا ہونے لگتے ہیں جن سے صاف طور پر پتہ لگتا ہے کہ اب یہ فنا ہو گا اور اس کی جگہ کوئی اور قائم مقام کھڑا ہو گا.پس وہ چیزیں جن کو خاص طور پر ایک لمبے عرصہ کے لئے پیدا نہیں کیا گیا جیسے سورج ہے یا چاند ہے ایک عرصہ گذرنے کے بعد بوڑھی ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور ان پر بڑھاپے کے آثار نظر آنے لگتے ہیں.یہ بڑھاپا انسان پر بھی آتا ہے حیوانات پر بھی آتا ہے درختوں پر بھی آتا ہے چراگاہوں پر بھی آتا ہے.پس الٰہی قانون یہ ہے کہ جو چیزیں مٹنے والی ہوتی ہیں ان پر اضمحلال اور بڑھاپے کے آثار ظاہر ہونے شروع ہو جاتے ہیں جن سے صاف پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا منشاء یہ ہے کہ اب وہ مٹ جائیں اور ان کی جگہ نئی چیزیں پیدا کی جائیں یہی قانون ہمیں سابق الہامی کتب کے متعلق کام کرتا ہوا نظر آتا ہے.چنانچہ قرآن کریم کو مستثنیٰ کرتے ہوئے کوئی ایک الہامی کتاب بھی ایسی نہیں جو اپنی اصل صورت میں دنیا میں پائی جاتی ہو.کتاب ایک ہوتی ہے مگر اس کے کسی نسخہ میں کچھ لکھا ہوتا ہے اور کسی نسخہ میں کچھ.انجیل کو ہی دیکھ لو آج کل چار اناجیل ہیں مگر ان چاروں اناجیل میں
Page 65
بیسیوں اختلافات پائے جاتے ہیں.پھر یہ چار انجیلیں بھی جس رنگ میں منتخب کی گئی ہیںوہ ظاہر کرتا ہے کہ ان کو الہامی قرار دینا کسی طرح بھی درست نہیں.جس وقت ان چار اناجیل کا انتخاب کیا گیا ہے اس وقت تین سو اناجیل عیسائیوں کے پاس موجود تھیں.(Dictionary of The Bible, By Dr.W.Smith Vol,11 P:943) وَاللہُ اَعْلَمُ یہ بات کہاں تک صحیح ہے مگر لوگ کہتے ہیں کہ پادریوں نے لمبی بحث کے بعد جب دیکھا کہ ہم میں یہ فیصلہ نہیں ہوسکتا کہ ان تین سو اناجیل میں سے کون سی مستندہیں اور کون سی غیر مستند تو انہوں نے ساری انجیلیں ایک میز پر رکھ دیں اور کتابوں پر زور سے ایک ڈنڈہ مارا.جو کتابیں اوپر رہ گئیں ان کو مستند قرار دے دیا اور جو نیچے گر گئیں ان کو غیر مستند قرار دے دیا.جس طرح مشہور ہے کہ ایک سست استاد بجائے لڑکوں کے پرچے پڑھنے کے اپنے سامنے میز پر پرچے رکھ کر زور سے ہاتھ مارتا.جن لڑکوں کے پر چے نیچے گر جاتے ان کو فیل کر دیتا اور جن لڑکوں کے پرچے اوپر رہ جاتے ان کو پاس کر دیتا.اسی طرح پادریوں نے کیاکہ انجیلیں اپنے سامنے رکھ لیں ڈنڈا ہاتھ میں لیا اور زور سے ان کتابوں پر مارا.جو نیچے گر گئیں ان کے متعلق سمجھ لیا کہ یہ غیر مستند ہیں اور جو اوپر رہ گئیں ان کو الہامی قرار دے دیا.لیکن اگراس واقعہ کو درست نہ سمجھا جائے اور چار اناجیل کا انتخاب پادریوں کے غور وفکر کا نتیجہ قرار دیا جائے تب بھی اگر انسانی غور و خوض ایک کتاب کو اصلی اور الہامی کہہ سکتا ہے تو وہی غور وخوض ایک نئی شریعت بھی بنا سکتا ہے.اور اگر انسانی غور وفکر کوئی شریعت نہیں بنا سکتا تو انسانی غور وخوض کے نتیجہ میں قطعی طور پر یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ فلاں یقینی الہام ہے.جب ایک ہی بات کے د۲و مدعی ہوں تو اس وقت ان میں سے کسی ایک کے حق میں اس وقت تک قطعاً فیصلہ نہیں دیا جا سکتا جب تک بیرونی اور اندرونی شہادت اس فیصلہ کی تائید میں موجود نہ ہو.بہرحال سابق الہامی کتب کے مٹنے کا سلسلہ ان کے ساتھ ہی شروع ہو گیا تھا.جو اس بات کا قطعی ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ کتب دائمی ہدایت کے لئے نازل نہیں ہوئی تھیں.اور تو اور خود ان مذاہب کے پیرو اور ان کتب پر ایمان رکھنے والے یہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ کتب ایک لمبے عرصہ سے مٹتی چلی آ رہی ہیں.خود عیسائی مانتے ہیں کہ اناجیل حضرت مسیح ناصریؑ کے کئی سو سال کے بعد تصنیف کی گئی ہیں اور انسانوں نے یہ کتابیں لکھی ہیں، آسمان سے نازل نہیں ہوئیں.پھر اناجیل کے نسخہ جات میں اختلاف خود عیسائی محققین بھی تسلیم کرتے ہیں.یہی حال تورات کا ہے.تورات کی اندرونی شہادت سے یہ امر ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ کتاب مٹ گئی تھی.اور اس کے مٹنے کا باعث یہ ہوا کہ چھٹی صدی قبل مسیحؑ یعنی چودھویں صدی ابراھیمیؑ کے آخر میں جب بخت نصر نے بیت المقدس کو جلا دیا تو تورات کی مقدس کتابیں بھی جل گئیں اور یہود قید ہو کر بابل میں لے جائے گئے.جہاں ستّر سال تک
Page 66
قید رہے.اس اسیری کے بعد وہ رہا ہوئے.اور حضرت عزیرؑ جن کی کتاب پرانے عہد نامہ میں پائی جاتی ہے انہوں نے اس کتاب کی تدوین دیگر احباب سمیت کی اور اپنی یادداشت کی بنا پر اسے لکھا.حضرت عزیرؑ کے نام سے ایک اور کتاب عیزڈراس ESDRAS یونانی زبان میں موجود ہے.جو حضرت عزیرؑ کی اس کتاب کے علاوہ ہے جو پرانے عہد نامہ میں پائی جاتی ہے.اگرچہ یہ کتاب موجودہ بائیبل کی کتابوں میں شامل نہیں مگر بائیبل سے کسی درجہ کم معتبر نہیں.چنانچہ بائیبل کا جو ضمیمہ بعد میں مرتب ہوا ہے اس میں عیزڈراس کو شامل کر لیا گیا ہے.اس کتاب کی دوسری کتاب کے چودھویں باب کو پڑھ کر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ کس طرح حضرت عزیرؑ نے اپنے پانچ ساتھیوں سمیت چالیس دن تک تورات کو دوباہ لکھا.کتاب مذکورہ کے چودھویں باب میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ درج ذیل ہے لکھا ہے:.تورات کا کلیۃً مٹ جانا اور اس کے بعد لکھا جانا ’’دیکھو اے خدا میں جاؤں گا جیسا کہ تو نے مجھے حکم دیا ہے.اور جو لوگ موجود ہیں میں ان کو فہمائش کروں گا.لیکن جو لوگ کہ بعد کو پیدا ہوں گے ان کو کون فہمائش کرے گا.اس طرح دنیا تاریکی میں ہے.اور جو لوگ اس میں رہتے ہیں بغیر روشنی کے ہیں کیونکہ تیرا قانون جل گیا.پس کوئی نہیں جانتا ان چیزوں کو جو تو کرتا ہے.اور ان کاموں کو جو شروع ہونے والے ہیں.لیکن اگر مجھ پر تیری مہربانی ہے تو تُو روح القدس کو مجھ میں بھیج اور میں لکھوں تمام جو کچھ کہ دنیا میں ابتداء سے ہوا ہے اور جو کچھ تیرے قانون میں لکھا تھا.تاکہ تیری راہ کو پاویں اور وہ لوگ جو اخیر زمانے میں ہوں گے زندہ رہیں اور اس نے مجھ کو یہ جواب دیا کہ جا اپنے راستے سے لوگوں کو اکٹھا کر اور ان سے کہہ وہ چالیس دن تک تجھ کو نہ ڈھونڈیں.لیکن دیکھ تو بہت سے صندوق کے تختے تیار کر اور اپنے ساتھ سیریاSARIA ڈبریا DABRIA سیلیمیاSELEMIA اکانس ECANUSاور اسیل ESIAL کو لے.اور ان پانچوں کو جو بہت تیزی سے لکھنے کو تیار ہیں اور یہاں آ.اور میں تیرے دل میں سمجھ کی شمع روشن کروں گا.جو نہ بجھے گی تا وقتیکہ وہ چیزیں پوری نہ ہوں جو تو لکھنی شروع کرے گا.‘‘ (آیت ۲تا ۲۵) غرض حضرت عزیرؑ اور پانچ زود نویس چالیس روز تک اوروں سے الگ تھلگ جا بیٹھے اور الہامی تائید سے انہوں نے چالیس دن میں دو سو چار کتابیں لکھیں (آیت ۴۴ ) جن میں نہ صرف تورات بلکہ وہ سب کتابیں جو حضرت موسٰی سے لے کر حضرت عزیرؑ تک کے پیغمبروں کی طرف منسوب تھیں شامل ہیں.
Page 67
مزید برآں یہ کہ تاریخی طور پر اس بات کا کوئی ثبوت پیش نہیں کیا جا سکتا کہ یہودیوںمیں تورات کو حفظ کرنے کا رواج ہو.بلکہ آج تک بھی یہود میں تورات کو حفظ کرنے کا عام رواج نہیں.اور جبکہ ان میں حفظ کا رواج ہی نہیں تھا یہ کیونکر قیاس کیا جا سکتا ہے کہ جن لوگوں نے دوبارہ تورات کو لکھا تھا انہوں نے اسے صحیح طور پر ہی لکھا تھا.تورات کی دوبارہ تدوین یہود کی جلا وطنی کے ایک لمبے عرصے بعد ہوئی ہے.بخت نصر یہود کو قید کر کے بابل لے گیا تھا اور وہاں اس نے ایک مدت تک ان کو اپنی غلامی میں رکھا.یہ مدت قریباً ساٹھ ستّر سال بنتی ہے (دیکھو تاریخ بائیبل مصنفہ پادری ولیم جی بلیکی صاحب.ڈی ڈی صفحہ ۴۰۱ ) اس کے بعد جب سائرس فارس اور مید کے بادشاہ کا زور ہوا تو اس کے ساتھ یہود نے خفیہ سمجھوتہ کیا اور اس کے حملہ آور ہونے پر اندر سے اس کی مدد کی.جس کی وجہ سے وہ بابل پر بہت جلد قابض ہو گیا.اس کے بعد انعام کے طور پر اس نے بنی اسرائیل کو اپنے ملک کی طرف واپس جانے کی اجازت دے دی.اس وقت عزرا نبی کا زمانہ تھا اور انہی کے زمانہ میں دوبارہ تورات لکھی گئی.یہ سارا عرصہ قریبًا سو سال کا بنتا ہے اور ہر شخص قیاس کر سکتا ہے کہ اس عرصہ میں کتنے لوگ زندہ رہے ہوں گے اور کتنے مر چکے ہوں گے.بخت نصر کے حملے اور عزرا نبی کے زمانہ میں سو سال کا جو وقفہ ہے اس میں اگر یہود کو تورات حفظ ہوتی تب بھی اتنے لمبے عرصہ کے بعد اس کا دوبارہ لکھا جانا یقینی نہیں سمجھا جا سکتا تھا.کیونکہ بہت سے لوگ مر چکے ہوں گے.لیکن ان میں تو حفظ کا رواج ہی نہیںتھا اس لئے انہوں نے جو کچھ لکھا قیاسی اور خیالی طور پر لکھا.تورات کے مٹنے کے متعلق اس کی اندرونی شہادت چنانچہ اس کا ثبوت بائیبل سے ہی اس رنگ میں ملتا ہے کہ پہلے تو یہ ذکر آتا ہے کہ موسٰی سے خدا نے یہ کہا اور موسٰی کو خدا نے یہ حکم دیا.مگر اس کے بعد لکھا ہے:.’’سو خدا وند کا بندہ موسٰی خداوند کے حکم کے موافق موآب کی سرزمین میں مر گیا اور اس نے اسے موآب کی ایک وادی میں بیت فغور کے مقابل گاڑا.پر آج کے دن تک کوئی اس کی قبر کو نہیں جانتا اور موسٰی اپنے مرنے کے وقت ایک سو بیس برس کا تھاکہ نہ اس کی آنکھیں دھندلائیںاور نہ اس کی تازگی جاتی رہی.‘‘ (استثناءباب۳۴ آیت ۵تا ۷) اب کیا کوئی شخص تسلیم کر سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ موسٰی سے کہہ رہا ہے کہ پھر موسٰی مر گیا اور اسے موآب کی ایک وادی میں گاڑا گیا.مگر اب اس کی قبر کا کہیں پتہ نہیں چلتا.صاف پتہ لگتا ہے کہ موسٰی کی وفات کے بعد کسی شخص نے یہ حالات لکھے ہیں اور اس وقت لکھے ہیں جب کہ موسٰی کی قبر کا بھی لوگوں کو علم نہیں رہا تھا کہ وہ کہاں گئی.آخر
Page 68
ایک نبی جو لاکھوں کا سردار تھا.جس پر لوگ اپنی جانیں قربان کرنے کے لئے ہر وقت تیار رہتے تھے.اس کی قبر اس وقت تک گم ہی کس طرح ہو سکتی تھی جب تک حکومت کا تسلسل ان میں پایا جاتا تھا.یہ الفاظ صاف بتا رہے ہیں کہ عزرا نبی کے زمانہ تک سو سال یہود نے جو جلاوطنی کی زندگی بسر کی تھی اس عرصہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر بھی مٹ گئی.جب بنی اسرائیل دوبارہ اپنے ملک میں واپس آئے اور تورات لکھی گئی تو اس وقت لکھنے والوں نے یہ بات بھی بڑھا دی کہ موسٰی کی قبر کا اب نشان نہیں رہا کہ وہ کہاں تھی.ورنہ وہ شخص جو قوم کا حاکم ہو، جو ایک جماعت کو قائم کرنے والا ہو، جو ان کی طاقتِ سیاسی اور علمی کا مرکز ہو، جو ان کو خاک سے اٹھا کر بامِ رفعت تک پہنچانے والا ہو اس کی قبر مٹ ہی کس طرح سکتی تھی.ہم تو دیکھتے ہیں ہمارے ملک میں معمولی معمولی پیروں اور فقیروں کی قبریں بھی نہیں مٹتیں اور موسٰی تو خدا کے نبی تھے.ایک قوم کے امام اور پیشوا تھے.شرعی نبی تھے.ان کی قبر اتنی جلدی کس طرح مٹ گئی.ہندوستان میں حضرت نظام الدین صاحبؒ اولیاء اور حضرت معین الدین صاحب چشتیؒ اور حضرت احمد صاحب سرہندی اور اسی طرح اور بڑے بڑے بزرگوں کے مقابر اب تک موجود ہیں حالانکہ مسلمانوں کی حکومت ہندوستان سے مٹ چکی ہے.مگر باوجود اس کے کہ اب ایک غیر حکومت ہے ان لوگوں کی قبریں اب تک محفوظ ہیں.ہاں اگر کوئی وقت ایسا آ جائے کہ ہندو غالب آ جائیں.وہ مسلمانوں کو ہندوستان میں سے نکال دیں.ان کے مقدس مقامات کو مٹا دیں اور پھر کسی دوسرے وقت مسلمان اس ملک میں واپس آئیں تو پھر بے شک وہ کہہ سکتے ہیں ہمیں اب یاد نہیں رہا کہ ہمارے فلاں فلاں بزرگ کی کہاں قبر تھی.پس یہ فقرہ جو استثناء کے آخر میں موجود ہے صاف بتا رہا ہے کہ تورات اس وقت لکھی گئی تھی جب یہود جلاوطنی سے واپس آئے تھے.اور چونکہ وہ قریبًا ایک سو سال تک باہر رہے اس لئے جب اپنے ملک میں آئے تو انہیں یاد نہ رہا کہ موسٰی کی قبر کہاں تھی.اسی لئے یہ لکھ دیا گیا کہ اب موسٰی کی قبر کا کہیں پتہ نہیں چلتا.یہ تورات کی اندرونی شہادت اس امر کا ثبوت ہے کہ تورات مٹ گئی تھی پھر دوبارہ اپنی یادداشت کی بناء پر اسے مرتّب کیا گیا.ویدوں کے غیر محفوظ ہونے پر ہندوؤں کے پنڈتوں کی شہادتیں ویدوں کا بھی یہی حال ہے.اوّل تو یہی فیصلہ نہیں ہوتا کہ وید تین ہیں یا چار.اور پھر وید کے منتروں میں بہت کچھ اختلاف پایا جاتا ہے.کسی وید میں کوئی منتر موجود ہوتا ہے اور کسی میں موجود نہیں ہوتا.کسی نسخہ میں وید کے زیادہ منتر ہوتے ہیں اور کسی میں کم.اس کے علاوہ خود ہندو علماء نے یہ تسلیم کیا ہے کہ وید اپنی اصلی شکل میں محفوظ نہیں بلکہ محرف ومبدّل ہو چکے
Page 69
ہیں.چنانچہ پنڈت شانتی دیو شاستری صاحب لکھتے ہیں:.’’پہلے تو آج تک یہ بھی فیصلہ نہیں ہوا کہ وید چار ہیں یا تین؟ منوسمرتی اور شتپتھ براہمن کی رو سے رِگوید، یجروید اور سام وید.یہ تین ہی وید ہیں.اور واجسنئی اُپنشد، برہمنواُپنشد اور مُنڈک اُپنشد کی رو سے چار وید ہیں.الـخ‘‘ (رسالہ گنگا.فروری۱۹۳۱ء صفحہ نمبر ۳۲۲) پھر ساہتیہ آچاریہ پنڈت مہیندر مشر صاحب تحریر فرماتے ہیں:.’’زمانہ کے لحاظ سے، ملک کے لحاظ سے اور تلاوت کے لحاظ سے ان (ویدوں ) میں بہت سا اختلاف ہو گیا ہے.اور آچاریوں (معلّموں) کی باہمی مخالفت کے باعث اور یگیہ میں ان کے استعمال کی وجہ سے بھی بہت سا اختلاف پڑ گیا ہے.اس طرح ہر ایک وید مختلف شاکھاؤں (نسخوں) میں منقسم ہو گیا ہے.رگوید کی بیس یا اکیس شاکھائیں (نسخے) یجروید کی ایک سو ایک شاکھائیں.سام وید کی ہزار شاکھائیں.اور اتھرووید کی نو۹ یا پند۱۵رہ شاکھائیں (نسخے) ہیں.‘‘ (رسالہ گنگا.جنوری ۱۹۳۲ء صفحہ ۴۸) پھر پنڈت راجا رام صاحب پروفیسر ڈی.اے.وی کالج لاہور لکھتے ہیں.’’سائن آچاریہ نے اس (اتھرووید کانڈ ۱۹) کے ۶۰ تا ۶۳ سُوکتوں کو چھوڑ دیا ہے (ان کی تفسیر نہیں کی) اور ۶۹،۷۰ سُوکتوں کے درمیان رگوید منڈل نمبر ۱ کا سُوکت ۹۹ بھی پایا جاتا ہے.ہٹبنی نے ایک بڑے مفصّل مضمون میں ثابت کیا ہے.کہ (اتھرووید کے آخری ۱۹،۲۰ کانڈ) پری ششٹ (ضمیمہ) ہیں.‘‘ (اتھرووید بھاش جلد دوم صفحہ ۸۳۱) اسی طرح پنڈت وَیدک مُنی صاحب لکھتے ہیں کہ.’’حقیقت میں جس قدر بری حالت اس اتھرووید کی ہوئی ہے اتنی اور کسی وید کی نہیں ہوئی.سائن آچاریہ کے بعد بھی کئی سُوکت اس میں ملا دیئے گئے ہیں.ملانے کا ڈھنگ بہت اچھا سوچا گیا ہے.وہ یہ کہ پہلے اس کے شروع اور آخر میں اتھ (شروع) اور اِتی (ختم)لکھ دیا جاتا ہے.جب کسی نے پوچھا تک نہ تب شروع آخر میں اتھ اِتی لکھنا بند کر دیا جاتا ہے.بس صرف اتنے سے وہ سنگہیتہ (مجموعہ) میں مل جاتا ہے.جیسے رگوید سنگہیتہ میں بالکھِلیہ سُوکت ملائے جا رہے ہیں.ویسے ہی اتھرووید کے آخر میں آج کل کُنتاپ سُوکت ملائے جا رہے ہیں.اگر پوچھا جائے کہ پانچویں انوواک سے لے کر کُنتاپ
Page 70
سُوکتوں سمیت جتنے سُوکت اتھرووید میں ملائے جا رہے ہیں وہ کہاں سے آئے؟ تو کوئی جواب نہیں ملتا.جہالت کا اتنا دور دورہ ہے کہ آخر میں ’’اتھرووید سنگہیتہ سما پتا ‘‘لکھا ہوا دیکھ کر ہی یہ یقین کر لیا جاتا ہے کہ بس جو کچھ اس خاتمہ تک چھپا ہوا یا لکھا ہوا ہے وہ سب اتھروسنگہیتہ ہے.یہ خیال نہیں کیا جاتا کہ چھاپنے والا یا لکھنے والا کون اور کتنی قابلیت رکھتا ہے.‘‘ (وید سروسوْ صفحہ ۹۷) پھر پنڈت مہیش چندر پرشاد بی.اے تحریر فرماتے ہیں.’’واجسنئی شُکل یجروید سنگہیتہ بالکل نئی طرز پر ہے.اس میں وید اور براہمن بھا گ الگ الگ پائے جاتے ہیں.اس میں چالیس ادھیائے ہیں.مگر لوگوں کا وشواش (یقین) ہے کہ ان میں ۱۸ اصل ہیں باقی بعد میں ملائے گئے ہیں.....ادھیائے ۱ سے ۱۸ تک کا بھاگ تیئتری سنگہیتہ و کرشن یجروید کے ساتھ نظم و نثر میں مطابقت رکھتا ہے.ان ۱۸ ادھیاؤں کے ہر ایک لفظ کی تشریح اس کے براہمن میں ملتی ہے.مگر باقی ۱۷ ادھیاؤں کے صرف تھوڑے تھوڑے منتروں پر ہی اس میں ٹپنی (نوٹ) پائی جاتی ہیں.کاتیائن نے ادھیائے ۲۶ سے ۳۵ تک کو کِھل (ملاوٹ) کے نام سے لکھا ہے.....ادھیائے ۱۹ سے ۲۵ ان میں بھی یگیہ کے طریقوں کا ذکر ہے.یہ تئیتری سنگہیتہ سے نہیں ملتے.۲۶ سے لے کر ۲۹ ادھیاؤں تک کچھ خاص طور پر انہی یگیوں کے متعلق منتروں کا ذکر ہے جن کے بارہ میں پہلے ادھیاؤں میں بیان ہے.اور اس سے خیال کیا جاتا ہے کہ یہ ضرور بعد میں ملا دیئے گئے ہیں.‘‘ (سنسکرت ساہتیہ کا اتہاس جلد دوم صفحہ ۱۶۰) الغرض خود ہندو علماء نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ وید اپنی شکل میں محفوظ نہیں بلکہ محرف و مبدل ہو چکے ہیں.پارسی لوگ مسلمانوں سے عداوت رکھنے کی وجہ سے کہہ دیا کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے ان کی مذہبی کتب کو جلا دیا تھا.جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب ان کے پاس زرتشتؑ کی الہامی کتاب کے صرف چند باب رہ گئے ہیں باقی کتاب سب ضائع ہو گئی.ہم تو اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ مسلمانوں نے ان کی مذہبی کتب کو جلایا ہے بلکہ خود پارسی کتب سے ثابت ہے کہ سکندر کے حملہ کے وقت ژنداوستا جلا دی گئی تھیں.لیکن اگر اس بات کو مان بھی لیا جائے تب بھی اس سے کم از کم اتنی بات تو ثابت ہو گئی کہ اب ان کے پاس زرتشت کا کلام مکمل صورت میں محفوظ نہیں جو کچھ ہے وہ اصل کتاب کا بہت تھوڑا سا حصہ ہے.غرض آج دنیا کے پردہ پر کوئی ایک کتاب بھی ایسی نہیں جس کے متعلق یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہو کہ جس شکل و صورت
Page 71
میں اس کتاب کو مذہب کے بانی نے پیش کیا تھا اسی شکل وصورت میں وہ اب دنیا کے سامنے موجود ہے.اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ خدا تعالیٰ نے ان کتابوں کے متعلق یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ وہ مٹ جائیں.کیونکہ خدا تعالیٰ چاہتاتھا ان کی جگہ اور کتاب نازل کرے.ورنہ اگر خدا تعالیٰ کا یہ منشا تھا کہ تورات دنیا میں قائم رہے تو جس خدا تعالیٰ نے موسٰی پر تورات نازل کی تھی کیا وہ اس بات پر قادر نہیں تھا کہ اس کے مٹ جانے کی صور ت میں دوبارہ ایک نبی موسٰی جیسا کھڑا کر دیتا.اور کہتا کہ چونکہ تورات مٹ گئی ہے اس لئے اب میں تجھ پر اصل تورات نازل کرتا ہوں اسے دنیا میں پھیلا.یا کیا خدا تعالیٰ یہ بھی نہیں کر سکتا تھا کہ جو لوگ تورات کو مٹانے لگے تھے ان کو خود اپنے عذاب سے ہلاک کر دیتا.اس طرح اگر ژنداوستا قائم رہنے والی چیزیں تھیں اور خدا تعالیٰ کا منشا یہ تھا کہ وہ دنیا میں محفوظ رہیں اور لوگ ان پر عمل کریں تو کیا سکندر کو خدا تعالیٰ اپنے عذاب سے کچل نہیں سکتا تھا.اگر خدا تعالیٰ کا یہ منشا تھا کہ ویدوں پر ہی عمل کیا جائے تو کیا خدا ان پنڈتوں اور وِدوانوں کو مار نہیں سکتا تھا جنہوں نے وید بدلنے کی کوشش کی.اگر خدا تعالیٰ کا منشا یہ تھا کہ تورات اپنی اصل صورت میں قائم رہے تو کیا خدا تعالیٰ بخت نصر کو شکست نہیں دے سکتا تھا.اگر خدا تعالیٰ کا منشا یہ تھا کہ دنیا کا انجیل پر ہی عمل رہے تو کیا اللہ تعالیٰ ان خرابیوں کو جو عیسائیوں نے انجیل میں پیدا کر دیں دور نہیں کر سکتا تھا.یقیناً خدا تعالیٰ ایسا کر سکتا تھا.مگر خدا تعالیٰ نے ان تغیرات کو ہونے دیا.کیونکہ خدا تعالیٰ کا خود یہ منشا تھا کہ یہ کتابیں دنیا میں محفوظ نہ رہیں.دوسری الہامی کتب کے مقابل قرآن مجید کی حفاظت دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جن چیزوں کو خدا تعالیٰ بچانے کا ارادہ رکھتا ہے دنیا لاکھ کوشش کرے وہ ان چیزوں کو بگاڑ نہیں سکتی.جب تک عیسٰیؑ کی تعلیم کو خدا تعالیٰ نے قائم رکھنا چاہا اس نے اس تعلیم کی حفاظت کی.جب تک زرتشت کی تعلیم سے اس نے کام لینا چاہا اس نے اس تعلیم کو دنیا سے مٹنے نہ دیا.مگر جب ان کتب کا کام ختم ہو گیا تو ان کتابوں سے اپنی حفاظت بھی اٹھالی.غرض اللہ تعالیٰ کی سنّت سے یہ ثابت ہے کہ وہ الہامی کتب کو اس وقت تک جب تک وہ دنیا کے لئے مفید اور نفع رساں رہتی ہیں ہر قسم کے تصرّف اور تحریف و الحاق سے محفوظ رکھتا ہے.مگر جب ان کا کام ختم ہو جاتا ہے تو دنیا ان میں بگاڑ پیدا کرنا شروع کر دیتی ہے.اسی طرح پیدائشِ عالم میں جو چیزیںعارضی فوائد کی حامل ہوں وہ ایک عرصہ کے بعد سڑ گل جاتی ہیں مگر جو چیزیں لمبے فوائد کی حامل ہوں وہ چلتی چلی جاتی ہیں.اسی دلیل کا ذکر اللہ تعالیٰ اس آیت میں کرتا ہے اور فرماتا ہے سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسٰۤى.ہم تجھے وہ تعلیم دیں گے جسے تو بھولے گا نہیں.یہاں تُو سے مراد صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ ساری اُمّت ِ محمدؐیہ مراد ہے.اور یہ قرآن کریم کا طریق بیان ہے کہ
Page 73
کے اشد تریں معاند بھی آج کھلے بندوں یہ تسلیم کرتے ہیں کہ قرآن کریم اسی شکل وصورت میں محفوظ ہے جس شکل و صورت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیش فرمایا.نولڈکے، سپرنگر اور ولیم میور سب نے اپنی کتابوں میں تسلیم کیا ہے کہ قطعی اور یقینی طور پر ہم سوائے قرآن کریم کے اور کسی کتاب کے متعلق یہ نہیں کہہ سکتے کہ جس شکل میں بانیٔ سلسلہ نے وہ کتاب پیش کی تھی اسی شکل میں وہ دنیا کے سامنے موجود ہے.صرف قرآن کریم ہی ایک ایسی کتاب ہے جس کے متعلق حتمی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ جس شکل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہؓ کو یہ کتاب دی تھی اسی شکل میں اب بھی محفوظ ہے.وہ لوگ چونکہ اس بات کے قائل نہیں کہ قرآن کریم خدا تعالیٰ نے نازل کیا ہے بلکہ وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کتاب خود بنائی ہے اس لئے وہ یہ تو نہیں کہتے کہ جس شکل میں یہ کتاب نازل ہوئی تھی اسی شکل میں محفوظ ہے مگر وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ جس شکل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کتاب پیش کی تھی اسی شکل میں یہ کتاب اب تک دنیا میں پائی جاتی ہے.چنانچہ سرولیم میور اپنی کتاب ’’دی کران‘‘(القرآن) میں لکھتے ہیں.’’یہ تمام ثبوت دل کو پوری تسلی دلا دیتے ہیں کہ وہ قرآن جسے ہم آج پڑھتے ہیں لفظاً لفظاً وہی ہے جسے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم ) نے لوگوں کو پڑھ کر سنایا تھا‘‘ (The Coran, its Composition and teachings p:40) پھر سرولیم میور اپنی کتاب لائف آف محمد میں لکھتے ہیں کہ.’’اب جو قرآن ہمارے ہاتھوں میں ہے گو یہ بالکل ممکن ہے کہ محمد (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ) نے اپنے زمانہ میں اسے خود بنایا ہو.اور بعض دفعہ اس میں خود ہی بعض تبدیلیاں بھی کر دی ہوں.مگر اس میں شبہ نہیں کہ یہ وہی قرآن ہے جو محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ہمیں دیا تھا.‘‘ (Life of Mahomet by Sir William Muir P:562,563) اسی طرح سے لکھتے ہیں کہ.ہم نہایت مضبوط قیاسات کی بنیاد پر کہہ سکتے ہیں کہ ہر ایک آیت جو قرآن میں ہے وہ اصلی ہے.اور محمد (آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم) کی غیر محرف تصنیف ہے.‘‘ (Life of Mahomet by Sir William Muir P:562,563)
Page 74
پھر نولڈکے جرمن مستشرق لکھتا ہے کہ.’’ممکن ہے کہ تحریر کی کوئی معمولی غلطیاں (یعنی طرزِ تحریر کی) ہوں تو ہوں.لیکن جو قرآن عثمانؓ نے دنیا کے سامنے پیش کیا تھا اس کا مضمون وہی ہے جو محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے پیش کیا تھا.گو اس کی ترتیب عجیب ہے.یورپین علماء کی یہ کوششیں کہ وہ ثابت کریں کہ قرآن میں بعد کے زمانہ میں بھی کوئی تبدیلی ہوئی.بالکل ناکام ثابت ہوئی ہیں.‘‘ (The Encyclopedia Britanica Under Word "Koran") قرآن مجید کے محفوظ ہونے پر یورپین علماء کی شہادتیں الغرض یورپین مصنفین نے بھی یہ تسلیم کیا ہے کہ جہاں تک قرآن کی ظاہری حفاظت کا سوال ہے اس میں کسی قسم کا شبہ نہیں کیا جا سکتا.بلکہ لفظاً لفظاً اور حرفاً حرفاً یہ وہی کتاب ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو پڑھ کر سنائی.غور کرو اور سوچو کہ یہ کتنی عظیم الشان پیشگوئی ہے جو ان چند الفاظ میں کی گئی کہ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسٰۤى اور پھر یہ پیشگوئی اس زمانہ میں کی گئی ہے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف چند لوگ ایمان لانے والے پائے جاتے تھے ساری دنیا آپؐکی مخالف تھی.اور وہ آپؐکے نام کو صفحۂ ہستی سے معدوم کرنے کے لئے تُلی ہوئی تھی.یہ نہیں کہ لاکھوں اور کروڑوں لوگ آپؐکے ساتھ ہوں اور آپؐایک جتھہ کو اپنے اردگرد دیکھ کر کہنے لگ گئے ہوں کہ اب اس کتاب کو کوئی مٹا نہیں سکتا بلکہ آپؐیہ پیشگوئی ایسی حالت میں کرتے ہیں جب آپؐدنیا کے ہر تیر کا نشانہ بنے ہوئے تھے اور آپؐپر ایمان لانے والے انگلیوں پر گنے جا سکتے تھے.ایسی نازک اور کمزور حالت میں آپؐفرماتے ہیں یہ قرآن دنیا میں قائم رہے گا اور کوئی شخص اس کو مٹانے کی قدرت نہیں رکھے گا.لاکھوں اور کروڑوں ماننے والوں کے ہوتے ہوئے وید بدل گئے.لاکھوں اور کروڑوں ماننے والوں کے ہوتے ہوئے تورات بدل گئی.لاکھوں اور کروڑوں ماننے والوں کے ہوتے ہوئے انجیل بدل گئی.لاکھوں اور کروڑوں ماننے والوں کے ہوتے ہوئے زرتشت کی کتابیں بدل گئیں.لیکن ایک انسان جس کے ساتھ صرف اسّی۸۰ ،نو۹۰ے آدمی ہیں.وہ ایک ایسے ملک میں جہاں حفاظت کا کوئی سامان نہ تھا.جہاں کسی قسم کی لائبریریاں نہ تھیں.جہاں کسی قسم کی تعلیم کا رواج نہ تھا.اعلان کرتا ہے کہ میری یہ کتاب ہمیشہ محفوظ رہے گی.قیامت تک قائم رہے گی اور دنیا اس کے ایک شوشہ کو بھی بدلنے کی طاقت نہیں رکھے گی.اگر مکہ کے لوگ پڑھے لکھے ہوتے تب بھی خیال کیا جا سکتا تھا کہ شائد مکہ کے لوگوں کی تعلیمی قابلیت کو دیکھ کر ایسا اعلان کیا گیا ہے.مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھو کہ اسلام ان
Page 75
لوگوں میں آیا جو لکھنا بھی نہیں جانتے تھے.ابتدائی مکی صحابہؓ میں سے صرف تین چار ایسے تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے.زیادہ سے زیادہ سات افراد سمجھ لو.اور کل جماعت جو آپؐ کے اردگرد تھی وہ اسّی۸۰ ،نو۹۰ے افراد سے زیادہ نہیں تھی.ایسی حالت میں یہ کتنی زبردست اور عظیم الشان پیشگوئی ہے کہ ہم تجھے قرآن پڑھائیں گے جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تُو قرآن کو بھولے گا نہیں.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے دوسروں کو خاص طور پر نہیںپڑھایا مگر تیرے لئے چونکہ ہماری ربوبیت اعلیٰ ظاہر ہوئی ہے اس لئے ہم تجھے ایسا اعلیٰ درس دیں گے جو تجھے کبھی نہیں بھولے گا.یعنی وہ کلام جو تجھ پر نازل ہو گا وہ ہمیشہ دنیا میں قائم رہے گا.اب دیکھو خدا تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کے کیسے سامان پیدا فرما دئیے کہ نہ صرف اس نے باطنی حفاظت کی بلکہ ظاہری حفاظت کے لئے بھی اس نے متعدد سامان پیدا کردیئے.قرآن مجید کے ظاہری حفاظت کے لئے خدا تعالیٰ کے پیدا کردہ چھ سامان پہلا سامان اختلاف امت مسلمہ پہلاسامان جو خدا تعالیٰ نے قرآن کریم کی ظاہری حفاظت کے لئے کیا وہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے معاً بعد مسلمانوں میں اختلاف پیدا ہو گیا.اگر ایک ہی متفق جتھہ حکومت کرتا رہتا تو ممکن تھا کہ کسی وقت ایمان کی کمزوری پیدا ہو کر وہ اپنی مرضی کے خلاف آیات قرآن کریم میں سے نکال دینے کی کوشش کرتا.مگر آنحضرت صلعم کی وفات کے معاً بعد ادھر انصار میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ ہم خلافت کے مستحق ہیں اور ادھر مہاجرین میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ ہم خلافت کے مستحق ہیں.اور اس کے نتیجہ میں ان میں رقابت اور اختلاف پیدا ہو گیا.اور وہ ایک دوسرے کے حالات کے کڑے نگران بن گئے.دیکھ لو اس وقت ہم میں اور غیر مبایعین میں اختلاف ہے.یہ اختلاف خواہ کس قدر تکلیف دہ ہو مگر اس میں کیا شبہ ہے کہ اس کے نتیجہ میں ہم ایک دوسرے کے نگران رہتے ہیں.ذرا کوئی بات ہو تو ہم شور مچا دیتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسّلام نے تو ایسا لکھا ہے اور تم اس کے خلاف بات پیش کر رہے ہو.اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے معًا بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی آپس میں رقابت پیدا کر دی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہر فریق دوسرے کے حالات کا نگران بن گیا اور کسی بے ایمان سے بے ایمان کو بھی جرأت نہ ہوئی کہ وہ قرآن کریم میں کسی قسم کی تحریف یا تغیر پیدا کر سکے.پھر اس وقت جب ابھی ہزاروں ہزار لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے زندہ تھے اللہ تعالیٰ نے شیعوں اور سنیوں کا اختلاف پیدا کر دیا.اور پھر خوارج کا گروہ نمودار ہو گیا.حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے آخری دَور میں شیعہ اور سُنّی دو گروہ بن چکے تھے.چنانچہ عبداللہ بن سباء شیعیت کے
Page 76
خیالات سے ہی متاثر تھا جس نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں اسلام کے خلاف بہت بڑا فتنہ برپا کیا.غرض رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے چوبیس ۲۴سال بعد جب ابھی ہزارہا صحابہؓ موجود تھے شیعہ اور سنّی کا نزاع شروع ہو گیا.اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے قریبًا ۳۲ سال بعد خوارج پیدا ہو گئے.یہ شیعہ سُنّی اور خوارج تینوں قرآن کریم پر ایمان رکھتے تھے اور اس وجہ سے تینوں ایک دوسرے کے رقیب اور نگران بن گئے جو قرآن کریم کی ظاہری حفاظت کا ایک عظیم الشان ذریعہ ثابت ہوا.پھر اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے شیعوں میں یہ خیال بھی پیدا کر دیا کہ قرآن کریم کا کچھ حصہ حضرت علیؓ کے پاس تھا مگر انہوں نے اس کو ظاہر نہ کیا.اب وہ حصہ امام غائب کے پاس ہے جب وہ ظاہر ہوں گے تو قرآن کریم کا وہ حصہ بھی اپنے ساتھ لائیں گے اب دیکھو یہ کیسی عجیب بات ہے کہ شیعہ قرآن کریم پر حملہ کرتے ہیں.وہ کہتے ہیں کہ اس کا ایک حصہ امام غائب کے پاس ہے مگر اس کے باوجود وہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ موجودہ قرآن کریم میں سے کوئی ایک آیت بھی کم نہیں.بلکہ لفظ بلفظ یہ وہی کلام ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا.باقی رہا ان کا یہ کہنا کہ قرآن میں سے دس پارے غائب ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ اگر دس پارے قرآن کریم میں نہیں ہیں تو اس کا لازمًا یہ مطلب ہے کہ قرآن کریم احکام شرعی کے لحاظ سے مکمل کتاب نہیں بلکہ اس میں ابھی کئی قسم کے نقائص ہیں.کیونکہ دس پارے جو غائب ہیں ان میں بھی آخر اللہ تعالیٰ کے احکام ہوں گے.اور جب کہ وہ پارے اس قرآن کے ساتھ شامل نہیں تو لازمًا اس میں کمی پائی جائے گی.اب سوال یہ ہے کہ وہ کون سے احکام ہیں جو قرآن کریم میں موجود نہیں ہیں.آخر دس پاروں کے غائب ہونے کے نتیجہ میں چاہیے تھا کہ بعض مذہبی مسائل نامکمل رہتے.بعض تمدنی مسائل حل نہ ہوتے.بعض عبادات سے تعلق رکھنے والی تعلیمیں اس میں موجود نہ ہوتیں.مگر ہمیں تو یہ دکھائی دیتا ہے کہ کوئی ایک مذہبی تعلیم بھی نہیں ہے جو قرآن کریم میں موجود نہ ہو.کوئی ایک تمدنی مسئلہ بھی نہیں ہے جسے قرآن کریم نے حل نہ کیا ہو اور عبادات سے تعلق رکھنے والی کوئی ایک تعلیم بھی نہیں ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بیان نہ کیا ہو.یہ قرآن اپنی تعلیم اور اپنے احکام اور اپنے اوامر اور اپنے نواہی کے لحاظ سے ہر طرح کامل ہے کسی قسم کا نقص اس میں پایا نہیں جاتا اور جب صورت حالات یہ ہے تو یہ کہنا کہ دس پارے غائب ہیں کسی طرح بھی صحیح نہیں ہو سکتا اگر دس پارے غائب ہوتے تو ضروری تھا کہ مسائل اسلامیہ میں کمی آ جاتی مگر ہمیں کوئی کمی نظر نہیں آتی.اور نہ شیعہ یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ موجودہ قرآن میں کسی قسم کی کمی پائی جاتی ہے یا کوئی ضروری بات اس میں بیان ہونے سے رہ گئی ہے.اور جب کہ وہ بھی موجودہ قرآن کے کامل ہونے کی گواہی دیتے ہیں اور ساتھ ہی کسی قسم کی کمی بیشی نہیں
Page 77
کر سکتے تو ان کا یہ دعویٰ خود بخود باطل ہو جاتا ہے کہ اس قرآن میں سے دس پارے غائب ہیں.بہرحال خدا تعالیٰ نے قرآن کریم کی ظاہری حفاظت کا ایک سامان یہ کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے معًا بعد مسلمانوں میں اختلاف پیدا کر دیا تاکہ وہ ایک دوسرے کے نگران رہیںاور کوئی فریق قرآن کریم میں دست برد نہ کر سکے.دوسرا سامان حفاظ کی کثرت دوسرا سامان خدا تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کے لئے یہ کیا کہ حفاظ و قرّاء کو اس کثرت کے ساتھ پیدا کر دیا کہ دنیا میں اس کی اور کہیں نظیر نہیں ملتی.قرآن کریم پہلی الہامی کتاب نہیں جو دنیا میں نازل ہوئی ہو بلکہ اس سے پہلے اور بھی کئی الہامی کتابیں نازل ہو چکی ہیں مگر کسی ایک کتاب کو بھی یہ بات میسر نہیں آئی کہ اسے ا س کے ماننے والوں نے حفظ کیا ہو.لیکن قرآن کریم وہ کتاب ہے جس کے لاکھوں حفاظ آج بھی دنیا میں موجو دہیں اور وہ شروع سے لے کر آخر تک اس کا ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف سنا سکتے ہیں.میں جب انگلستان گیا تو کسی شخص نے مجھ سے کہا کہ قرآن پر ایک بڑا زمانہ گذر چکا ہے اور پھر اس وقت تو تحریر کا بھی رواج نہیں تھا اس لئے قرآن کریم کے متعلق یقینی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ وہی کتاب ہے جو آج سے تیرہ سو سال پہلے دنیا کے سامنے پیش کی گئی.میں ۱۹۲۴ء میں انگلستان گیا تھا اور اس وقت ناصر احمد کی عمر ۱۵سال کی تھی اور وہ قرآن کریم کو حفظ کر چکا تھا.میں نے اسے جواب دیا کہ بے شک تحریر کا اس وقت رواج نہیں تھا مگر حفاظ کا وجود پایا جاتا تھا لوگ اس کتاب کو حفظ کر لیتے تھے اور اس طرح سینہ بہ سینہ نسلاً بعد نسلٍ لوگ اس کو یاد رکھتے چلے جاتے تھے.اس نے کہا اتنی بڑی کتاب کو کون حفظ کر سکتا ہے.میں نے کہا عربوں کا حافظہ تو دنیا میں مشہور ہے.لاکھوں اشعار ایک ایک شخص کو یاد ہوا کرتے تھے.ان کے لئے قرآن کریم کو حفظ کر لینا کوئی مشکل امر نہیں تھا.مگر تم عربوں کا ذکر جانے دو.میرا لڑکا جس کی عمر صرف پندرہ سال ہے اس نے سارا قرآن کریم حفظ کیا ہوا ہے.یہ سن کر وہ حیران ہو گیا کہ اتنی بڑی کتاب کو اس نے کس طرح حفظ کر لیا.میں نے کہا ہمارے ہاں تو قرآن کریم حفظ کرنے کا عام رواج ہے.لوگ اخلاص اور نیک نیتی کے ساتھ اپنے بچوں کو قرآن کریم حفظ کراتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا ان کو حاصل ہو گئی.یورپین لوگ اس بات کا قیاس بھی نہیں کر سکتے جس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں یہ نعمت ملی ہی نہیں اور اس وجہ سے وہ سمجھ ہی نہیں سکتے کہ اتنی بڑی کتاب کو کس طرح حفظ کیا جا سکتا ہے.مسلمانوں میں حفظ قرآن کا اس قدر رواج تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک غزوہ میں دشمن نے ستر حفاظ مار ڈالے تھے.حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام اپنے دادا مرزا گل محمد صاحب کے متعلق بیان فرمایا کرتے تھے کہ ان کے دربار میں پانچ سو حافظ تھا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ سپاہی وغیرہ ہر قسم کے پیشہ کے لوگ جو ان کے
Page 78
دربار میں تھے ان میں سے ایک کثیر حصہ نے قرآن کریم کو حفظ کیا ہوا تھا.اس زمانہ میں مسلمانوں کی حالت سخت کمزور ہے اور وہ تنزّل کے دَور سے گذر رہے ہیں.مگر اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں لاکھوں لاکھ حفاظ ہندوستان میں سے ہی نکل سکتے ہیں.غرض دوسرا ذریعہ قرآن کریم کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ حفاظ و قرّاء کی کثرت پیدا کر دی اور یہ چیز بھی ایسی ہے جو کسی کے بس کی نہیں.غرض قرآن کریم کی حفاظت کا ایک سامان خدا تعالیٰ نے یہ کیا کہ دلوں میں اس کے حفظ کی رغبت پیدا کر دی.اور اس طرح لاکھوں لوگوں کے سینوں میں اس کا ایک ایک لفظ بلکہ زبر اور زیر تک محفوظ کر دی.قرآن مجید کی حفاظت کا تیسرا سامان یعنی اس کا عجیب اسلوب بیان تیسرے رغبت کے علاوہ بعض طرز کلام ایسا ہوتا ہے جس کا حفظ کرنا آسان ہوتا ہے اور بعض طرزِ کلام ایسا ہوتا ہے جس کا حفظ کرنا نہایت مشکل ہوتا ہے.قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے ایسے اسلوب پر نازل کیا ہے کہ نثر ہونے کے باوجود شعروں کی طرح ہے اور اس کا یاد کرنا نہایت آسان ہے دنیا کے کسی لڑکے کو تم اردو کا ایک صفحہ دے دو اور ایک صفحہ قرآن کریم کا دے دو اور اسے کہو کہ وہ ان دونوں کو یاد کرے تو قرآن کریم کا صفحہ وہ جلد یاد کر لے گا.لیکن اردو کا صفحہ یاد کرنا اس کے لئے بہت مشکل ہو گا.پھر اگر کچھ دیر گذرنے کے بعد اس سے دوبارہ سنو کہ اس کے حافظہ میں قرآن اور اردو کہاں تک محفوظ ہے تو اردو والے صفحہ میں سے وہ شاید ایک سطر بھی سنا نہیں سکے گا لیکن قرآن کو وہ اچھی طرح سنا دے گا.پس تیسرا ذریعہ قرآن کریم کی ظاہری حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار کیا کہ اسے ایسا اسلوب کلام بخشا جس کا یاد کرنا بہت ہی آسان ہے.تھوڑے ہی دن ہوئے ایک یورپین مصنف کا میں نے ایک حوالہ پڑھا ہے.وہ لکھتا ہے قرآن کریم کے تراجم کرنے میں یورپین مصنف اس لئے غلطی کھا جاتے ہیں کہ وہ اس کے سٹائل کو نہیں دیکھتے.قرآن کریم کا سٹائل ایسا غضب کا ہے کہ وہ نہ نظم ہے نہ نثر دونوں سے علیحدہ چیز ہے.مگر چونکہ یورپین مصنف اس سٹائل کو نہیں سمجھتے اس لئے وہ قرآن کریم کے معانی کرنے میںٹھوکر کھا جاتے ہیں.پھر وہ کہتا ہے قرآن کریم کو ترجمہ سے سمجھنے کی کوشش کرنا اور اس کے معانی کو استنباط کرنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی زبور کی آیات کے نثر کے ترجمہ سے ان کا مطلب سمجھنا چاہے.زبور بھی ایسے سٹائل میں ہے جو شاعرانہ ہے وہ کہتا ہے زبور کا اگر نثری رنگ میں کوئی شخص ترجمہ کر دے تو دوسرے لوگ نہیں سمجھ سکیں گے کہ ز بور میں کیا کہا گیا ہے.اسی طرح قرآن کریم کو ایسے خوشنما رنگ میں ڈھالا گیا ہے کہ محض نثر میں اس کا ترجمہ کرنے سے اس کے باریک مطالب تک انسانی ذہن نہیں پہنچ سکتا.غرض قرآن کریم کو ایسا سٹائل بخشا گیا ہے کہ اس کا حفظ کرنا اور سب عبارتوں سے
Page 80
اس سے اندازہ لگا کر کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت تک قرآن کریم کی یقیناً لاکھوں کاپیاں تیار ہو چکی ہوں گی جو سفر اور حضر میں مسلمان اپنے پاس رکھتے ہوں گے.پس یہ بھی ایک ذریعہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کے متعلق اختیار کیا.قرآن مجید کی حفاظت کا پانچوں سامان پانچواں سامان اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کے لئے یہ کر دیا کہ اسلام شروع میں ہی مختلف ممالک میں پھیل گیا.چنانچہ ابھی ہزاروں صحابہ ؓ زندہ تھے کہ اسلام شام میں بھی پہنچ گیا.عراق میں بھی پہنچ گیا.فلسطین میں بھی پہنچ گیا.انطاکیہ میں بھی پہنچ گیا.ایران میں بھی پہنچ گیا.مصر میں بھی پہنچ گیا.اسی طرح افریقہ کے مختلف علاقوں تک اسلام کا نام جا پہنچا.یہاں تک کہ صحابہؓ چین تک گئے اور انہوں نے اسلام کی اشاعت کی.ہندوستان میں آئے اور یہاں انہوں نے اسلام پھیلایا.سندھ میں جہاں ہماری زمینیں ہیں وہاں ایک گاؤں ہے جسے دیہہ صابو کہا جاتا ہے یعنی صحابہؓ کا گاؤں اور وہاں ایک قبر بھی ہے جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ کسی صحابیؓ کی قبر ہے.ادھر تاریخی طور پر یہ ثابت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہؓ ہندوستان میں آئے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ممکن ہے یہ بات درست ہی ہو کہ وہ کسی صحابیؓکی قبر ہے.گویقینی شواہد پر ہم اس بات کی بنیاد نہیں رکھ سکتے.مگر یہ روایتیںخواہ کس قدر کمزور اور ضیعف ہوں بہرحال پرانے زمانہ سے چلی آ رہی ہیں اور ان سے معلوم ہوتا ہے کہ ابتدائی زمانہ میں ہی صحابہؓ عرب سے نکل کر دنیا کے مختلف ممالک میں پھیل گئے اور انہوں نے اسلام کو پھیلانا شروع کر دیا.اور چونکہ وہ جہاں بھی جاتے قرآن کریم کی کاپیاں اپنے ساتھ رکھتے تھے.اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس ذریعہ سے قرآن کریم کی ہزاروں کاپیاں یک دم سارے جہان میں پھیلا دیںاور مختلف اقوام اس کی حفاظت میں مشغول ہو گئیں.یہ بھی ایک ذریعہ تھا جو قرآن کریم کی ظاہری حفاظت کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا.حفاظت قرآن کا چھٹا سامان چھٹا سامان اللہ تعالیٰ نے حفاظتِ قرآن کریم کے متعلق یہ پیدا کیا کہ شروع میں ہی عربی زبان مختلف ممالک میں پھیل گئی اور اس وجہ سے ترجمہ کرنے کی ضرورت نہ رہی.ہر ملک کے لوگ عربی زبان میں ہی قرآن کریم کو سمجھ سکتے تھے.فرض کرو اگر عربوں کا فائدہ قرآن کریم کے بگاڑنے میں ہوتا تب بھی وہ اس کی جرأت نہیں کر سکتے تھے.کیونکہ فلسطینی نگرانی کے لئے موجود تھے.عراق اور شام اور مصر کے لوگ ان کی نگرانی کے لئے موجود تھے اور وہ یہ جرأت ہی نہیں کر سکتے تھے کہ اس میں کسی قسم کی تبدیلی کر دیں.غرض عربی زبان کے مختلف ممالک میں پھیل جانے کی وجہ سے اس کی نگرانی مختلف قوموں کے ذمہ لگ گئی اور اس طرح
Page 81
قرآن کریم ہر قسم کی تحریف اور ہر قسم کے تغیّر و الحاق سے محفوظ رہا.یہ چھ ایسے سامان ہیں جو دنیا کی اور کسی قوم کی الہامی کتاب کو میسر نہیں آئے.صرف قرآن کریم کو ہی اللہ تعالیٰ نے یہ سامان عطا فرمائے ہیں.پس سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسٰۤى میں اس سوال کا جواب آ گیا کہ ہم کیوں اسے قولِ فصل کو تسلیم کریں اور کیوں یہ نہ مانیں کہ یہ کتاب صرف وقتی طور پر کامل کتاب ہے.ایک زمانہ گذرنے کے بعد پھر کوئی اور کتاب آ جائے گی.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کتاب کے بعد اور کوئی کتاب نہیں آ سکتی.ہمارا اس کتاب کی حفاظت کے متعلق وعدہ کرنا اور پھر اس کی حفاظت کے لئے ہر قسم کے سامانوں کا پیدا کر دینا خود اس بات کا ثبوت ہو گا کہ اب الٰہی منشاء یہی ہے کہ یہ کتاب قیامت تک قائم رہے.اگر اللہ تعالیٰ اس کتاب کو بھی سابق الہامی کتب کی طرح منسوخ کر دینے والا ہوتا تو وہ اس کو بھی پہلی کتابوں کی طرح بگڑنے دیتا اور وہ اس کی حفاظت کے سامان مہیا نہ کرتا.مگر خدا نے اس کو بگڑنے نہیں دیا کیونکہ یہ مستقل فائدہ پہنچانے والی کتاب ہے.اور جس چیز کا فائدہ مستقل ہو وہ الٰہی قانون کے ماتحت فنا نہیں ہو سکتی.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَمَّا مَا یَنْفَعُ النَّاسَ فَیَمْکُثُ فِی الْاَرْضِ (الرّعد:۱۸) جو چیز لوگوں کے لئے نفع رساں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ وہ اس کو زمین میں قائم رکھتا ہے.چونکہ قرآن کریم کی حفاظت کی گئی ہے اس لئے یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ یہ کتاب دنیا میں ہمیشہ قائم رہے گی.کبھی منسوخ یا ناقابلِ عمل نہیں ہو گی.اب ایک سوال رہ جاتا ہے کہ اگر اس کتاب نے ہمیشہ رہنا ہے تو پھر بتائیے کسی موعود کی کیا ضرورت ہے.اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے اگلے حصہ میں دیا ہے.اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ١ؕ اِنَّهٗ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَ مَا يَخْفٰىؕ۰۰۸ سوائے اس کے جو اللہ (بھلانا) چاہے.وہ یقیناً ظاہر کو بھی جانتا ہے اور اسے بھی جو مخفی ہو.تفسیر.اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ کی تشریح سابق مفسرین کے نزدیک اس آیت کے متعلق بوجہ ان معنوں کے نہ کرنے کے جن کو میں نے اوپر بیان کیا ہے مفسرین کو سخت دقت پیش آئی ہے اور وہ حیران ہوئے ہیں کہ اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰہُ کے اس جگہ کیا معنے ہوئے.کیا قرآن کا کچھ حصہ اڑ جائے گا کہ خدا تعالیٰ نے فَلَاتَنْسٰۤى کے ساتھ اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰہُ بھی کہہ دیا.اس دقت کو حل کرنے کے لئے بعض نے تو کہہ دیا ہے کہ
Page 82
اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰہُ سے منسوخ آیات مراد ہیں (تفسیر البحر المحیط زیر آیت ’’ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسٰۤى‘‘).مگر یہ درست نہیں اس لئے کہ جن آیات کو منسوخ قرار دیا جاتا ہے وہ یا تو قرآن کریم میں آج تک لکھی ہوئی موجود ہیں یا اگر اس عقیدہ کے رکھنے والوں کے قول کے مطابق اگر وہ منسوخ التلاوۃ بھی ہیں تو آج تک تفسیروں میں لکھی ہوئی ہیں.مگر خدا تعالیٰ اس جگہ فرماتا ہے کہ وہ بھول جائیں گی.جب وہ سب کی سب قرآن کریم میں یا تفسیروں میں موجود ہیں تو بھول کس طرح جائیں گی.یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ قرآن کریم میں کوئی آیت منسوخ بھی ہے.ہم قرآن کریم کے ایک ایک لفظ کو قابلِ عمل سمجھتے ہیں.لیکن وہ لوگ جو قرآن کریم میں ناسخ منسوخ کے قائل ہیں میں ان کا ذکر کر رہا ہوں.کہ ان کا یہ استدلال درست نہیں.اس لئے کہ فَلَاتَنْسٰۤى کے ساتھ اِلَّا مَاشَآءَ اللّٰہُ کا ـذکر کیا گیا ہے اور نسخ اوّل تو بھولنے کو نہیں کہتے.پھر جب کہ وہ سب آیات جن کو منسوخ قرار دیا جاتا ہے یا تو قرآن کریم میں یا تفاسیر میں موجود اور لکھی ہوئی ہیں تو وہ بھول کس طرح گئیں.واقعہ بھی یہ ہے کہ وہ سب اسی طرح موجود ہیں اور کسی کو بھی بھولی نہیں.پس یہ معنے تو درست نہیں ہو سکتے.بعض نے کہا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ شاذونادر کے طور پر تُو بھول جائے گا اور پھر تجھے یاد آجائے گا لیکن یہ بھی درست نہیں ہو سکتا.(تفسیر البحر المحیط زیر آیت ’’ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسٰۤى‘‘)اس لئے کہ شاذونادر کا بھولنا بھی بھولنا ہی ہوتا ہے اور اگر وہ یاد آجاتا ہے تو وہ بھولنا کہلا ہی نہیں سکتا.پھر قرآن کریم تو اسی وقت سب کو سنا دیا اور لکھا دیا جا تا تھا.یہ ہو کس طرح سکتا تھا کہ شاذونادر کے طور پر اس کا کوئی حصہ بھول جائے.بعض کہتے ہیں کہ فَلَاتَنْسٰۤى میں الف فاصلہ کا ہے اور اصل میںنہی ہے یعنی فَلَا تَنْسَ تو بھولیو نہیں.مگر یہ تاویل بعید اور خلافِ محاورۂ زبان ہے.بعض مفسرین نے یہ معنے کئے ہیں کہ یہاں اِلَّا بمعنے نفی ہے کیونکہ عرب کبھی قلت کا لفظ نفی کے لئے بھی استعمال کر لیتے ہیں.اِلَّا قَلِیْلًا سے مراد یہ ہوتی ہے کہ بالکل نہیں.اسی طرح اِلَّا مَاشَآءَ اللّٰہُ سے مراد یہی ہے کہ تو بالکل نہیں بھولے گا(تفسیر الکشاف زیر آیت ’’ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسٰۤى‘‘).مگر یہ تاویل درست نہیں کیونکہ نفی کے معنے اِلَّا اسی وقت دیتا ہے جب کہ اس کے بعد کوئی لفظ قلت پر دلالت کرتا ہو.مگر یہاں تو ایک مضمون بعد میں بیان کیا گیا ہے.اور خدا تعالیٰ کی مشیت کا حوالہ دیا گیا ہے.زمخشری نے کشاف میں یہ معنے کئے ہیں کہ اِلَّا مَاشَآءَ اللّٰہُ کا اس آیت میں کوئی مفہوم نہیں یعنی اس سے مراد کوئی استثناء نہیں بلکہ کُلّی طور پر نسیان کی نفی مراد ہے اور یہ ایسی ہی
Page 84
یاد رکھنا وہ ضروری نہیں سمجھتا الفاظ بے شک اسے یاد ہوتے ہیں مگر مضمون اس کی نگاہ میں کوئی اہمیت نہیں ر کھتا.اس سے جب پوچھا جائے کہ کیا فلاں شعر تمہیں یاد ہے اور پوچھنے والا شعر پڑھ کر بھی سنا دے اور وہ جواب میں کہے کہ میں نے اس شعر کو بھلا دیا ہے تو اس کے یہ معنے نہیں ہوں گے کہ اس شعر کے الفاظ میرے ذہن میں نہیں بلکہ یہ معنے ہوں گے کہ اس شعر سے میرا کوئی تعلق نہیں رہا.میں نے اس کے مضمون کو بھلا دیا ہے.یا مثلاً بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص دوسرے سے پوچھتا ہے تمہارے فلاں دوست کا کیا حال ہے.اور وہ جواب میں کہتا ہے میں نے اسے بھلا دیا ہے.اب اس کے یہ معنے نہیں ہوتے کہ اس کا نام اسے یاد نہیں رہا یا اس کی شکل اس کے ذہن میں مستحضر نہیں رہی.نام اس وقت لیا جا رہا ہوتا ہے اور شکل بھی بہرحال اس کے ذہن میں موجود ہوتی ہے اس وقت اس کا یہ کہنا کہ میں نے اس کو بھلا دیا ہے صرف یہ مفہوم رکھتا ہے کہ میرا اب اس سے کوئی تعلق نہیں.تو نسیان کا لفظ صرف الفاظ بھولنے کے معنوں میں ہی استعمال نہیں ہوتا بلکہ حقیقت کو بھول جانے کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے.اور قرآن کریم میں اس کی مثال موجو دہے.اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق فرماتا ہے.فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهٗ عَزْمًا (طٰہٰ: ۱۱۶) وہ ہمارے حکم کو بھول گیا اور ہم نے اس کے اندر عزم نہیں پایا.یہاں نسیان اور عزم نہ پائے جانے سے مراد یہ ہے کہ کسی خاص ارادہ اور نیت سے اس نے یہ کام نہیں کیا تھا.یہ مراد نہیں کہ ہمارا حکم اس کے ذہن سے نکل گیا تھا بلکہ جیسا کہ دوسری آیات سے ثابت ہے حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو بھولے نہیں تھے بلکہ یہ حکم انہیں خوب یاد تھا اور نہ صرف یا دتھا بلکہ شیطان نے انہیں یہ حکم یاد کرایا تھا.چنانچہ سورۂ اعراف میں ذکر آتا ہے کہ جب شیطان حضرت آدم علیہ السلام کو ورغلانے کے لئے ان کے پاس آیا تو کہا مَا نَهٰىكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ اِلَّاۤ اَنْ تَكُوْنَا مَلَكَيْنِ اَوْ تَكُوْنَا مِنَ الْخٰلِدِيْنَ.وَ قَاسَمَهُمَاۤ اِنِّيْ لَكُمَا لَمِنَ النّٰصِحِيْنَ (الاعراف:۲۱،۲۲) اب دیکھو شیطان ان کو بہکا رہا ہے مگر اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کا حکم انہیں یاد کرا رہا ہے اور کہتا ہے کہ بےشک خدا تعالیٰ نے تمہیں اس درخت کے پاس جانے سے منع کیا تھا مگر یہ ممانعت کا حکم محض اس لئے تھا کہ اگر تم دونوں اس درخت کے قریب گئے تو فرشتے بن جاؤ گے.یا خدا تعالیٰ کو یہ ڈر تھا کہ اگر تم اس درخت کے قریب گئے تو تم ابدی زندگی حاصل کر لو گے اس لئے خدا تعالیٰ نے تمہیں منع کیا اور کہا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا.گویا منع توضرور کیا تھا مگر اس لئے منع کیا تھا کہ خدا یہ نہیں چاہتا تھا کہ تم مَلک بن جاؤ اور خدا یہ نہیں چاہتا تھا کہ تم خالدین میں سے بن جاؤ.یہی اس ممانعت میں حکمت تھی مگر یہ دونوں باتیں اچھی ہیں بری نہیں ہیں اس لئے اگر مَلک بننے کے لئے یا ابدی زندگی حاصل کرنے کے لئے اس حکم کو توڑ دیا جائے تو یہ نقصان دہ بات نہیں
Page 85
ہو گی بلکہ انجام کے لحاظ سے نہایت مفید ہو گی.وَ قَاسَمَهُمَاۤ اِنِّيْ لَكُمَا لَمِنَ النّٰصِحِيْنَ اور اس نے قسمیں کھا کھا کر یقین دلایا کہ یہ دونوں باتیں تمہارے فائدہ کی ہیں.خدا تعالیٰ نے اگر روکا تھا تو کسی ابتلا یا امتحان کے طور پر روکا تھا ورنہ خدا تعالیٰ کا قرب ہمیشہ ہی اچھا ہوتا ہے.اگر تم فرشتے بن جاؤ تو بہرحال خدا تعالیٰ کا قرب تمہیں زیادہ حاصل ہو گا.اور اگر تم خالد بن جاؤ تب بھی اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے تم ہمیشہ خدا تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو گے اور اس کے قرب اور محبت میں بڑھتے رہو گے.خدا کا روکنا اور ممانعت کا حکم دینا تو ایک وقتی طور پر امتحان لینے کے لئے تھا ہمیشہ کے لئے نہیں تھا.یہ فقرات صاف بتا رہے ہیں کہ آدمؑ نہ صرف خدا تعالیٰ کے حکم کو بھولا نہیں تھا بلکہ اس وقت جب اس نے اس حکم کی خلاف ورزی کی شیطان نے خدا تعالیٰ کا یہ حکم اسے یاد کرایا اور بار بار قسمیں کھاکر یقین دلایا کہ خدا تعالیٰ نے اگر روکا تھا تو اس لئے کہ اسے ڈر تھا تم مَلک نہ بن جاؤ اور تم ابدی زندگی حاصل نہ کر لو اور یہ دونوں باتیں ایسی ہیں جو ہر حالت میں انسان کے لئے مفید ہی مفید ہیں.خدا تعالیٰ کے دائمی قرب اور فرشتوں کی سی زندگی بسر کرنے سے بڑھ کر اور کون سی نعمت ہو سکتی ہے.اگر انسان فرشتہ بن جائے اور اگر اسے دائمی زندگی حاصل ہو جائے تو خدا تعالیٰ کا قرب اسے بہرحال پہلے سے زیادہ حاصل ہو جائے گا اور جبکہ انسان کی پیدائش کی اصل غرض خدا تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہی ہے تو اس حکم کے متعلق یہی سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ عارضی طور پر ابتلا کے طور پر دیا گیا تھا.اس لئے نہیں تھا کہ اس پر ہمیشہ کے لئے عمل کیا جائے.اِلَّا مَاشَآءَ اللّٰہُ میں جس بھولانے کی طرف اشارہ ہے وہ روح ہے نہ احکام یہ وہ واقعہ ہے جس کا ذکرکرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهٗ عَزْمًا (طٰہٰ: ۱۱۶) آدمؑ ہمارے حکم کو بھول گیا.حالانکہ جہاں تک حکم کے الفاظ کا تعلق ہے قرآن کریم سے ہی ثابت ہے کہ آدمؑ اس کو نہیں بھولا.بلکہ شیطان جو آدمؑ کو بہکانے کا موجب ہوا اس نے خود یہ حکم یاد کرایا اور کہا کہ خدا نے روکا تو تھا مگر اس کی کچھ اور وجہ تھی.پس یہاں نسیان سے مراد نسیانِ الفاظ نہیں بلکہ نسیانِ اہمیتِ حکم ہے.اور نَسِیَ سے یہ مراد ہے کہ آدمؑ ہمارے حکم کو لفظاً نہیں بلکہ معناً بھول گیا.ہمارے حکم کی اصل روح کو اس نے نظر انداز کر دیا اور وہ اس کی خلاف ورزی کا مرتکب ہو گیا.اس آیت میں بھی اِلَّا سے اس دوسری قسم کے نسیان کی طرف ہی اشارہ ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسٰۤى ہم تجھ کو قرآن کریم پڑھائیں گے ( اور تجھ سے مراد جیسا کہ میں بتا چکا ہوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ اُمّتِ محمدیہ مراد ہے) اور تو اس قرآن کو نہیں بھولے گا.یعنی تیری اُمّت اس قرآن کو نہیں بھولے گی.اِلَّا مَاشَآءَ اللّٰہُ مگر وہ حصہ جو خدا چاہے گا بھول جائے گا.یعنی ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مسلمان لفظاً تو قرآن کریم
Page 86
کو یاد رکھیں گے مگر معناً اس کو بھول جائیں گے.الفاظ کو تو قائم رکھیں گے مگر آدمؑ کی طرح الفاظ کی روح کو بھول جائیں گے.جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یُوْشِکُ اَنْ یَّاْتِیَ عَلَی النَّاسِ زَمَانٌ لَا یَبْقٰی مِنَ الْاِسْلَامِ اِلَّا اسْـمُہٗ وَلَا یَبْقٰی مِنَ الْقُرْاٰنِ اِلَّا رَسْـمُہٗ (مشکاۃ المصابیح کتاب العلم فصل الثالث) یعنی ایک زمانہ ایسا آئے گا جب قرآن کے صرف الفاظ باقی رہ جائیں گے.ایمان اور اسلام کی روح اڑ جائے گی.اسی کا اِلَّا مَاشَآءَ اللّٰہُ میں استثناء کیا گیا ہے.اور بتایا گیا ہے کہ تم اس قرآن کو نہیں بھولو گے مگر ایک قسم کا نسیان ہو سکے گا.یہ مطلب نہیں کہ سورۃ اعراف نہیں مٹے گی اور سورۃ مائدہ مٹ جائے گی یا سورۃ کوثر نہیں مٹے گی اور سورۃ الناس مٹ جائے گی.بلکہ مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ تو باقی رہیں گے مگر معنے اڑ جائیں گے پس اِلَّا اس جگہ قرآن کریم کے الفاظ کے ٹکڑوں کے استثناء کے طور پر استعمال نہیں ہوا بلکہ دو قسم کی حفاظتوں میں سے ایک قسم کی حفاظت کی نسبت استعمال ہوا ہے.اور اس میں قولِ فصل کے متعلق اس اعتراض کا جواب دیا گیا ہے کہ اگر یہ قولِ فصل ہے تو پھر کسی اور مامور کی کیا ضرورت ہے.سو بتایا کہ قرآن کریم کے ظاہر کی حفاظت غیر فاصل کا وعدہ ہے اس کی معنوی غیر فاصل حفاظت کا وعدہ نہیں.وہ مستقل تو ہو گی مگر غیر فاصل نہیں.جب اللہ تعالیٰ لوگوں کو نااہل پائے گا.مغزِ قرآن اڑ جائے گا.جسے واپس لانے کے لئے پھر ایک مامور کی ضرورت ہو گی.اِنَّهٗ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَ مَا يَخْفٰى اس آیت میں اللہ تعالیٰ وجہ بیان فرماتا ہے کہ کیوں ایک زمانہ میں مغزِ قرآن دنیا سے اٹھ جائے گا.اور صرف الفاظ لوگوں کے پاس باقی رہ جائیں گے.فرماتا ہے خدا لوگوں کی قلبی اور ان کی ظاہری حالت کو خوب جانتا ہے.جب تک مسلمانوں کا ظاہر بھی درست رہے گا اور ان کا باطن بھی درست رہے گا قرآن ظاہر میں بھی محفوظ رہے گا اور باطن میں بھی محفوظ رہے گا.جب مسلمان صرف ظاہر میں مسلمان کہلائیں گے ان کا باطن خراب ہو جائے گا.قرآن کا بھی صرف ظاہر ٹھیک رہے گا اس کا باطن یعنی مغز ان سے اٹھ جائے گا.خدا ظاہر کو بھی جانتا ہے اور باطن کو بھی جانتا ہے.جب مسلمانوں کے دل میںایمان نہیں رہے گا تواللہ تعالیٰ قرآن کریم کے معنے ان پر کیوں کھولے گا.قرآن کریم تو ایک نور ہے جو صرف نورانی لوگوں پر کھل سکتا ہے.بد عمل اور بےایمان لوگ اس کے معارف سے آگاہ نہیں ہو سکتے.پس اِلَّا مَاشَآءَ اللّٰہُ میں مسلمانوں کی آخری زمانہ کی حالت کا نقشہ کھینچا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں پر ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے جب وہ الفاظ کو تو یاد رکھیں گے مگر عمل کرنا بھول جائیں گے.یہ مطلب نہیں کہ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ کے الفاظ بھول جائیں گے بلکہ مطلب
Page 87
یہ ہے کہ وہ حمد کا لفظ منہ سے تو بولیں گے مگر ان کے دل اللہ تعالیٰ کی حمد سے بالکل خالی ہوں گے.وہ رب کا لفظ تو استعمال کریں گے مگر اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر کامل ایمان ان کے دلوںمیں نہیں ہو گا.وہ ظاہر میں مسلمان کہلائیں گے.پس قرآن کریم ظاہر میں محفوظ رہے گا.لیکن چونکہ وہ باطن میں اسلام کو کھو دیں گے.قرآن کا مغز بھی ان سے اٹھ جائے گا.غرض اس جگہ یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن کریم کی حفاظت دو قسم کی ہے ایک لفظی حفاظت اور ایک معنوی حفاظت لفظی حفاظت کے متعلق یہ وعد ہ ہے کہ وہ غیر فاصل ہو گی.کوئی زمانہ ایسا نہیں آئے گا جب قرآن کریم کے الفاظ میں تغیر و تبدل ہو جائے.مگر معنوی غیر فاصل حفاظت کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی وعدہ نہیں.بےشک وہ حفاظت بھی مستقل طور پر ہو گی مگر غیر فاصل نہیں ہو گی.بلکہ اُمّت محمدیہ بگڑ جائے گی تو کوئی نبی آجائے گا پھر بگڑے گی تو پھر کوئی نبی آجائے گا.ظاہری حفاظت بغیر کسی وقفہ کے ہو گی.لیکن باطنی حفاظت گو ہو گی قیامت تک مگر وقفوں کے ساتھ ہو گی.اِنَّهٗ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَ مَا يَخْفٰى میں اس بات کا جواب کہ قولِ فصل کے بعدکسی وحی کی کیا ضرورت ہے اس آیت میں تفصیلی طور پر اس اعتراض کا جواب آگیا ہے کہ قولِ فصل کے بعد کسی الہام یا کسی مامور کی بعثت کی کیا ضرورت ہے.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے چونکہ ظاہر میں یہ شریعت ہمیشہ محفوظ رہے گی اس لئے ظاہر میں کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں ہو گی.لیکن باطن میں چونکہ نقص پیدا ہوتا رہے گا اس لئے ضروری ہے کہ افہام و تفہیم کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے انبیاؑء اور مامور مبعوث ہوتے رہیں جو قرآن کریم کی معنوی حفاظت کا فرض سرانجام دیں.اور جس چیز کو لوگ بھول چکے ہوں اس کو دوبارہ الٰہی تائید سے تازہ کر دیں.اگر مسلمانوں میں خرابی پیدا نہ ہونی ہوتی تو کسی مامور کی ضرورت بھی نہیں تھی.لیکن چونکہ مسلمانوں کے متعلق یہ مقدر ہے کہ ایک عرصہ گذرنے کے بعد ان میں خرابی پیدا ہو جائے گی.اسلام کی حقیقت محو ہو جائے گی.محض رسمی طور پر لوگ مسلمان کہلائیں گے قرآن کی طرف اپنے آپ کو منسوب کریں گے لیکن مغز ِقرآن دنیا سے اٹھ جائے گا اور مسلمانوں کی عملی حالت سخت خراب ہو جائے گی اس لئے ضروری ہے کہ دوبارہ اسلام کو زندہ کرنے اور قرآن کریم کی تعلیم کو قائم کرنے کے لئے اس کی طرف سے کوئی مامور مبعوث ہو.
Page 88
وَ نُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرٰى ۚۖ۰۰۹ اور ہم (اے مسلمان) تیرے لئے (کامیابیوں اور) آسانیوں کا حصول آسان کر دیں گے.حلّ لُغات.نُیَسِّـرُ.نُیَسِّـرُ یَسَّـرَ سے مضارع جمع متکلّم کا صیغہ ہے اور یَسَّـرَ الشَّیْءَ لِفُلَانٍ کے معنے ہوتے ہیں سَھَّلَہٗ لَہٗ وَدَفَعَہٗ لَہٗ.اس کے لئے کسی چیز کے حصول کو آسان کر دیا گیا اور وہ چیز اسے مہیا کر دی گئی.یَکُوْنُ فِی الْـخَیْرِ وَالشَّـرِّ.یہ لفظ خیر کے لئے بھی استعمال کر لیتے ہیں اورشرّ کے لئے بھی (اقرب ) یعنی یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یَسَّـرَہٗ لِلْعُسْـرٰی اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یَسَّـرَہٗ لِلْیُسْـرٰی.یُسْـرٰی.اور یُسْـرٰی کے معنے ہیں اَلسَّھْلُ (مفردات) آسان.پس نُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرٰى کے یہ معنے ہوئے کہ ہم تیرے لئے آسانی پیدا کر دیں گے یُسْـرٰی کے بارے میں.یا ہم تجھ کو مہیا کر دیں گے یُسْـرٰی.یعنی تجھ کو جو چیز ملے گی وہ یُسْـرٰی ہو گی اور اس وجہ سے اس پر عمل کرنا اور اس تعلیم سے تعلق رکھنا لوگوں کے لئے آسان ہوگا.تفسیر.یُسْـرٰی سےمراد احکامِ شریعت میں آسانی اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ مضمون بیان فرماتا ہے کہ تیرے دین کی حفاظت اور اس کے دائمی طور پر قیام کا یہ بھی ایک ذریعہ ہے کہ اس میں یُسْـرٰی یعنی احکامِ شریعت میں سے زیادہ سہل کو مدنظر رکھا گیا ہے.سابق مضمون کے تسلسل میں یہ ایک نئی دلیل اس بات کی بیان کی گئی ہے کہ قرآن کریم ہمیشہ محفوظ رہے گا.جس طرح کئی قسم کے ظاہری سامان اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے کئے ہیں اسی طرح اس کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے ایک یہ سامان بھی پیدا کیا ہے کہ اس میں ہر فطرت کا لحاظ رکھا گیا ہے.اور اس لئے یہ تعلیم ہر زمانہ میں کامیاب طور پر چل سکتی ہے.لوگ اگر خود چھوڑ دیں تو اور بات ہے ورنہ قرآن کریم میں کوئی ایسی تعلیم نہیں جس میں فطرتِ انسانی کے کسی پہلو کو نظر انداز کیا گیا ہو یا کوئی ایسی تعلیم دی گئی ہو جس پر عمل کرنا لوگوں کو بارِ خاطر معلوم ہو.بلکہ اس کی تعلیم انسانی فطرت کے مطابق ہے اور اس میں ایسی سہولتیں موجود ہیں جن کی وجہ سے ہر فطرت کا انسان اس کے احکام پر عمل کر سکتا ہے.چنانچہ دیکھ لو یہ یُسْـرٰی ہی ہے کہ کسی وقت کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا حکم ہے اور کسی وقت بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت ہے.کسی وقت لیٹ کر نماز پڑھنے کی اجازت ہے اور کسی وقت اشاروں اشاروں میں ہی نماز پڑھ لینے کی اجازت ہے.اگر صرف اتنا ہی حکم دے دیا جاتا کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھو تو بیمار اور معذور لوگ اس پر عمل نہ کر سکتے اور گناہ گار
Page 89
ہوجاتے.مگر اللہ تعالیٰ نے ہر حالت کو مدنظر رکھتے ہوئے اپنے احکام میں ایسی لچک پیدا کر دی ہے کہ کوئی انسان ایسا نہیں جو یہ کہہ سکے کہ میرے لئے اسلام کے فلاں حکم پر عمل کرنا ناممکن ہے.یا مثلاً جہاد پر قرآن کریم نے بڑا زور دیا ہے مگر ساتھ ہی کہہ دیا ہے کہ وہ لُولے اور لنگڑے جو جہاد پر جانے کی طاقت نہیں رکھتے اگر دل میں اسلام کا درد رکھتے ہوں اور خواہش رکھتے ہیں کہ کاش ان کے اندر طاقت ہوتی تو وہ بھی جہاد میں شریک ہوتے اس قسم کے لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں جہاد کے ثواب میں شریک ہوں گے.غرض خدا تعالیٰ فرماتا ہے ہم تم کو لے جائیں گے یا ہم تم کو قریب کر دیں گے یُسْـرٰی تعلیم کے.یہ یُسْـرٰی قرآن کریم ہے.کیا بلحاظ اس کے کہ اس کو حفظ کرنا نہایت آسان ہے اور کیا بلحاظ اس کے کہ عمل کرنا نہایت آسان ہے.یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے جس کا جواب دینا نہایت ضروری ہے اور وہ یہ کہ اسلام میں تو روزانہ پانچ وقت نمازیں پڑھنے کا حکم ہے اور عیسائیوں میں ہفتہ میں صرف ایک دن تھوڑی دیر کے لئے عبادت کرنے کا حکم ہے.اب بتاؤ ان دونوں میں سے کون سی آسان تعلیم ہوئی.اسلام کی جس میں روزانہ پانچ وقت نماز پڑھنے کا حکم ہے یا عیسائیت کی جس میں ہفتہ میں صرف ایک دن تھوڑی دیر کے لئے عبادت کرنے کا حکم ہے.اس کے متعلق یاد رکھنا چاہیے کہ یُسْـرٰی ایسی چیز کو بھی کہتے ہیں جو خواہ جسمانی طور پر تکلیف دِہ ہو لیکن روحانی طور انسان کے لئے نہایت فرحت بخش ہو.ہمارے ہاں لوگ کہا کرتے ہیں کہ میرے لئے تو مر جانا آسان ہے بہ نسبت فلاں دوست کو چھوڑ دینے کے.اب دیکھو جہاں تک جسم کا تعلق ہے مرنا آسان نہیں اور کسی دوست کو چھوڑ دینا اس کے مقابلہ میں بالکل معمولی چیز ہے.موت کی تلخی جسم کے لئے بڑی سخت ہوتی ہے مگر اس کے باوجود انسان کہتا ہے کہ میرے لئے مرنا آسان ہے مگر میں اس دوست کو نہیں چھوڑ سکتا.جس کے معنے یہ ہوتے ہیں کہ میرے قلب کو اس سے اپنی زندگی سے بھی زیادہ اُنس اور پیار ہے.اسی طرح اسلام میں گو روزانہ پانچ وقت نمازیں پڑھنے کا حکم ہے مگر چونکہ نماز میں انسان کا اپنا روحانی فائدہ ہے اس لئے پانچ نمازیں پڑھنا اس کے لئے آسان ہو جائے گا بہ نسبت اس ایک نماز کے جو ہفتہ میں صرف ایک دن پڑھنی پڑے.مومن کہے گا کہ میرے لئے یہ پانچ نمازیں بہ نسبت ہفتہ والی صرف ایک نماز کے زیادہ آسان ہیں کیونکہ صرف ایک نماز کے نتیجہ میں میرا خدا مجھ سے چھوٹ جاتا ہے اور پانچ نمازوں کے نتیجہ میں میرا خدا مجھ سے مل جاتا ہے.پس یُسْـرٰی سے مراد ظاہری آسانی نہیں بلکہ روحانی فوائد کے اعتبار سے آسانی مراد ہے کہ جب انسان روحانی فوائد دیکھتا ہے تو عمل اس کے لئے آسان ہو جاتا ہے.
Page 90
نُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرٰى میں اس طرف اشارہ کہ قرآن مجید نے احکام کی حکمت بھی بیان کی ہے وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرٰى کے ایک یہ بھی معنے ہیں کہ ہم تجھے ایسی تعلیم دیں گے جس میں صرف احکام ہی نہیں ہوں گے بلکہ ان احکام کے ساتھ ساتھ ان کی حکمتیں بھی بیان ہوں گی اس لئے وہ احکام بجائے گراں گذرنے کے بالکل آسان معلوم ہوں گے.اور لوگ ان کو چھوڑنا پسند نہیں کریں گے.یہ ایک قدرتی بات ہے کہ جب کسی حکم کی حکمت بیان کر دی جائے.اور انسان پر یہ واضح ہو جائے کہ یہ حکم میرے فائد ہ کے لئے دیا گیا ہے تو جس شوق سے وہ حکمت معلوم کرنے کے بعد عمل کرتا ہے اس شوق سے وہ حکمت معلوم کئے بغیر عمل نہیں کر سکتا.یہی بات اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمائی ہے.کہ ہم نے ہر حکم کی حکمت بیان کر دی ہے اور اس وجہ سے اس تعلیم پر عمل لوگوں کے لئے نہایت آسان ہو گیا ہے.غرض نُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرٰى کے تین معنے ہوئے یہ بھی کہ ہم نے اس قرآن کا حفظ کرنا آسان کر دیا ہے یہ بھی کہ ہم نے احکام کے ساتھ ان کی حکمتیں بھی بیان کر دی ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کے لئے عمل آسان ہو گیا ہے اور یہ بھی کہ ہم نے ایسی تعلیم نازل کی ہے جس میں ہر فطرت کا لحاظ رکھا گیا ہے اور ضرورت کے مطابق اس میں لچک پیدا ہو جاتی ہے.چنانچہ شریعت اسلامیہ کے تمام احکام کو دیکھ لو اسلام نے کسی ایک حکم کے متعلق بھی یہ نہیں کہا کہ اس میں حالات کے لحاظ سے کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی.نماز کے متعلق اسلام نے نہایت ہی تاکیدی احکام دیئے ہیں.لیکن اگر کوئی شخص بے ہوش ہو جائے تو اس کے لئے کوئی حکم نہیں رہتا.اگر کوئی شخص پاگل ہو جائے تو اس کے متعلق یہ حکم نہیں ہو گا کہ وہ بھی نماز پڑھے.بلکہ اگر کوئی شخص نماز پڑھتے پڑھتے پاگل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ جب تک پاگل رہے ایسا ہی سمجھا جائے گا جیسے وہ نماز پڑھتا رہا ہے.اور اسے وہی ثواب ملے گا جو نماز پڑھنے والوں کو ملتا ہے.غرض کوئی مشکل ایسی نہیں جس کا علاج اسلام میں موجود نہ ہو.بے شک اسلام نے یہ کہا ہے کہ نمازکے لئے مسجد میں آؤ لیکن اگر مسجد نہ ہو تو اسلام کہتا ہے گھر پر ہی پڑھ لو.اگر کوئی خاص جگہ عبادت کے لئے نہیں ملتی تو مٹی پر ہی کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لو.وضو نہیں کر سکتے تو تیمّم کر لو.پھر امام کے متعلق کوئی خاص شرائط نہیں سوائے اس کے کہ وہ متقی ہو.مگر عیسائیوں میں صرف ایک دن کی عبادت کے متعلق ہی کئی قسم کی شرائط پائی جاتی ہیں مثلاً عیسائیوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ گِرجا میں جائیں.یہ ضروری ہے کہ پادری آئے جو انہیں عبادت کرائے.اور پھر ضروری ہے کہ پادری ایسا ہو جو ڈگری یافتہ ہو اور جس نے کالے رنگ کا کوٹ پہنا ہوا ہو.اب بتاؤ کالے رنگ کے کوٹ کا عبادت سے کیا تعلق ہے یا کسی ڈگری کے ہونے یا نہ ہونے کا عبادت کے ساتھ کیا جوڑ ہے.لیکن اسی قسم کی پابندیاں ہیں جو عیسائیت نے عبادت پر عائد کی ہوئی ہیں.اس کے مقابلہ میں
Page 92
اچھا نکلے گا یا برا نکلے گا.اس مشکل کو دیکھتے ہوئے بعض مفسرین نے اس کے یہ معنے کئے ہیںکہ نصیحت کرو اگر فائدہ نہ ہو تو بے شک چھوڑ دو(بحر محیط زیر آیت ’’ فَذَكِّرْ اِنْ نَّفَعَتِ الذِّكْرٰى ‘‘).یہ معنے کہاں تک درست ہیں اس کے لئے ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھنا چاہیے کہ آیا آپؐکا یہ طریق تھا کہ آپؐبرابر نصیحت کرتے چلے جاتے تھے یا جب آپؐنصیحت کا کوئی فائدہ نہ دیکھتے تو چھوڑ دیتے تھے.یہ سورۃ مکی ہے اور ابتدائی زمانۂ نبوت میں نازل ہونے والی سورتوں میں سے ہے.مگر باوجود اس آیت کے نزول کے ہم دیکھتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں کو برابر تیرہ سال تک نصیحت کرتے چلے گئے.اور آپؐنے ایک دن کے لئے بھی ان کو سمجھانا ترک نہیں کیا.اگر اس آیت کے یہی معنی ہوں کہ نصیحت کا اگر فائدہ نہ ہو تو بےشک اسے چھوڑ دیا جائے تو اس کے معنے یہ بنتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ اس آیت پر عمل نہیں کیا.آپؐدیکھتے تھے کہ نصیحت کا کوئی فائدہ نہیں نکل رہا مگر اس کے باوجود آپؐسمجھاتے چلے جاتے تھے.پھر یہود کو اسلام میں داخل کرنے کے لئے آپؐنے کتنا زور لگایا بار بار ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے تھے.بار بار ان کو وعظ و نصیحت کرتے تھے اور کبھی اس بنا پر اپنی کوششوں کو ترک نہیں کرتے تھے کہ جب وعظ و نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تو سمجھانے کا کیا فائدہ.پس فَذَكِّرْ اِنْ نَّفَعَتِ الذِّكْرٰى کے یہ معنے نہیں ہیں کہ ایک دفعہ نصیحت کرو اور کوئی نہ مانے تو اسے چھوڑ دو.جس طرح پرانے زمانہ کی عورتیں بعض دفعہ دوسرے کو سمجھانے کے لئے کوئی بات کہتیں اور وہ نہ مانتا تو کہتیں ’’جہنم میں جاؤ ہمیں کیا‘‘ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ان معنو ں کے خلاف ہے.اس لئے کوئی وجہ نہیں کہ ان معنوں کو درست قرار دیا جائے ہاں اتنا بے شک درست ہے کہ ہنسی اور مذاق کرنے والے لوگوں کی مجالس سے اٹھ جانے کا حکم ہے مگر یہ حکم نصیحت نہ ماننے کی وجہ سے نہیں بلکہ تمسخر کرنے اور شعائر اللہ کی ہتک کرنے کی وجہ سے ہے.سنجیدہ لوگوں کو تبلیغ کرتے جانے کا ہی حکم ہے.بعض مفسرین کہتے ہیں کہ گو اِنْ کے معنے شرط کے ہیں مگر اس جگہ یہ مکفّرین کے لئے توبیخ کے طور پر استعمال ہوئے ہیں یعنی اس امر کے اظہار کے لئے کہ کفار بڑے ضدی ہیں اور نصیحت کم ہی مانتے ہیںاس لئے ان میں سے بہت سے لوگ ضد کرتے جائیں گے.غرض اِنْ نصیحت کی حد بندی کے لئے نہیں ہے بلکہ جن کو نصیحت کی جائے گی ان کی سنگ دلی کے اظہار کے لئے ہے.یہ معنے محاورہ کے مطابق ہیں اور ان سے اشکال بھی دور ہو جاتا ہے.بعض نحویوں نے یوں تاویل کی ہے کہ اس جگہ اِنْ اِذْ کے معنوں میں استعمال ہوا ہے جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ کُنْتُمْ مُّؤْمِنِیْنَ (اٰل عـمران:۱۴۰) یہاں یہ معنے نہیں کہ اگر تم مومن ہو تو
Page 93
تم غالب آ جاؤ گے.کیونکہ اس آیت سے قبل اللہ تعالیٰ ان کو مومن قرار دے چکا ہے.پس اس کے یہ معنے تو ہو نہیں سکتے کہ اگر تم میں ایمان ہوا تو تمہیں غلبہ حاصل ہو جائے گا بلکہ اس کے معنے یہ ہیں کہ وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ کُنْتُمْ مُّؤْمِنِیْنَ یعنی جب کہ تم مومن ہو اور خدا اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہو تو یہ ہو کس طرح سکتا ہے کہ تم مغلوب ہو جاؤ اور کفار تم پر غالب آجائیں.خدا تعالیٰ نے تمہیں دولت ایمان سے مشرف فرمایا ہے اس لئے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تمہیں کفار پر غلبہ حاصل نہ ہو اسی طرح اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَذَكِّرْ اِنْ نَّفَعَتِ الذِّكْرٰى جب کہ یہ یقینی اور تحقیقی بات ہے کہ ذِکْرٰی سے ہمیشہ نفع پہنچتا ہے تو پھر اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ذِکْرٰی کو چھوڑیو نہیں بلکہ دن اور رات اس میں مشغول رہیو.اگر آج نہیں تو کل اور کل نہیں تو پرسوں ان لوگوں کے سینے کھل جائیں گے اور یہ ہدایت کو قبول کر لیں گے.پس یہاں یہ حکم نہیں دیا گیا کہ ایک دو دفعہ نصیحت کرو اگر فائدہ نہ ہو تو چھوڑ دو.بلکہ حکم یہ دیا گیا ہے کہ ہمیشہ نصیحت کرتے جاؤ کیونکہ نصیحت ایسی چیز ہے جو ضرور دل پر اثر کرتی ہے.سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَّخْشٰى ۙ۰۰۱۱ جو (خدا تعالیٰ سے) ڈرتا ہے وہ یقیناً نصیحت حاصل کرے گا.تفسیر.انسانی حالات پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ قلبی کیفیات ہمیشہ بدلتی رہتی ہیں.کبھی اس پر خشیت کی حالت طاری ہوتی ہے اور کبھی عدم خشیت کی.جب انسانی قلب پر الٰہی خشیت طاری ہو اور اللہ تعالیٰ کے جلال اور اس کی ہیبت سے وہ متاثر ہو تو اس وقت معمولی سے معمولی نصیحت بھی بڑا گہرا اثر کرتی ہے لیکن اگر دل میں خشیت نہ ہو تو اعلیٰ سے اعلیٰ نصیحت بھی بےکار ہو جاتی ہے.ہر شخص کو اپنی زندگی میں اس کا تجربہ ہو گا کہ بعض دفعہ ایک بات کسی شخص کو بیسیوں دفعہ کہی جاتی ہے مگر اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا اور بعض دفعہ صرف ایک مرتبہ کہی جاتی ہے تو فوراً اس کا اثر ظاہر ہو جاتا ہے.اس کی وجہ یہی ہے کہ انسانی قلب کی حالت بدلتی رہتی ہے کبھی اس پر خشیت کی گھڑیاں آتی ہیں اور کبھی عدم خشیت کی.اس آیت میں اللہ تعالیٰ وعظ و نصیحت کے متعلق دوام سے کام لینے کی وجہ بیان فرماتا ہے اور بتاتا ہے کہ چونکہ انسانی قلب پر خشیت کے اوقات بھی آتے رہتے ہیںاور کوئی شخص نہیں جانتا کہ سامع پر وہ گھڑی جب ہدایت کے لئے اس کا سینہ کھل جائے کب آئے گی اس لئے تمہارا فرض ہے کہ تم ہمیشہ نصیحت کرتے رہو کیونکہ تم نہیں جانتے دوسرے کی ہدایت کا کون سا وقت مقرر ہے.
Page 94
وَ يَتَجَنَّبُهَا الْاَشْقَىۙ۰۰۱۲ اور (اس کے برخلاف) جو نہایت بدبخت ہو گا وہ اس سے گریز ہی کرتا رہے گا.حلّ لُغات.یَتَجَنَّبُھَا.یَتَجَنَّبُـھَا یَتَجَنَّبُ تَـجَنَّبَ سے مضارع کا صیغہ ہے اور تَـجَنَّبَہُ کے معنے ہیں بَعُدَ عَنْہُ یعنی اس سے دور ہو گیا (اقرب) پس یَتَجَنَّبُ کے معنے ہوں گے وہ دور ہوجائے گا.اَلْاَشْقٰی.اَشْقٰی شَقِیَ سے ہے اور شَقِیَ الرَّجُلُ (یَشْقٰی.شَقًا وَشَقَاءً وَشَقَاوَۃً وَشِقَاوَۃً وَشَقْوَۃً وَشِقْوَۃً) کے معنے ہیں کَانَ شَقِیًّا ضِدُّ سَعِدَ فَھُوَ شَقِیٌّ جَـمْعُہٗ اَشْقِیَاءُ (اقرب) یعنی شقاو ت سعادت کے مقابل کا لفظ ہے.جیسے سعید کے مقابلہ میں شقی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے معنے اس شخص کے ہوتے ہیں جس میں نیکی کی قابلیت مر جاتی ہے.مفردات والے کہتے ہیں کَمَا اَنّ السَّعَادَۃَ فِی الْاَصْلِ ضَـرْبَانِ سَعَادَۃٌ اُخْرَوِیَّۃٌ وَسَعَادَۃٌ دُنْیَوِیَّۃٌ ثُمَّ السَّعَادَۃُ الدُّنْیَوِیَّۃُ ثَلَاثَۃُ اَضْرُبٍ سَعَادَۃٌ نَفْسِیَّۃٌ وَبَدَنِیَّۃٌ وَخَارِجِیَّۃٌ کَذٰلِکَ الشَّقَاوَۃُ عَلٰی ھٰذِہِ الْاَضْرُبِ وَفِی الشَّقَاوَۃِ الْاُخْرَوِیَّۃِ قَالَ فَلَا يَضِلُّ وَ لَا يَشْقٰى(طٰہٰ:۱۲۴)...وَفِی الدُّنْیَوِیَّۃِ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا۠ مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقٰى(طٰہٰ:۱۱۸) قَالَ بَعْضُھُمْ قَدْ یُوْضَعُ الشَّقَاءُ مَوْضِعَ التَّعَبِ نَـحْوَ شَقَیْتُ فِیْ کَذَا وَکُلُّ شَقَاوَۃٍ تَعَبٌ وَلَیْسَ کُلُّ تَعَبٍ شَقَاوَۃً فَالتَّعَبُ اَعَمُّ مِنَ الشَّقَاوَۃِ (مفردات).یعنی شقاوت سعادت کے مقابل کی چیز ہے.جس طرح سعادت دو قسم کی ہوتی ہے ایک سعادت اخروی اور ایک سعادت دنیوی اسی طرح شقاوت بھی دو قسم کی ہوتی ہے ایک شقاوت اخروی اور ایک شقاوت دنیوی.پھر دنیوی سعادت آگے تین قسم کی ہوتی ہے.ایک سعادت نفسیہ یعنی انسانی نفس میں نیکی اور شرافت پائی جائے.ایک سعادت بدنیہ یعنی انسانی جسم باصحت اور تندرست ہو.کسی قسم کی بیماری اس میں نہ ہو اور ایک سعادت خارجیہ یعنی انسان کے دوست اور اس کے رشتہ دار آرام میں ہوں.اس کے متعلقین کو کسی قسم کا دکھ نہ ہو.ملک میں بد امنی نہ ہو اور اس طرح خارجی طور پر اسے سکون اور اطمینان حاصل ہو.اگر انسانی نفس تو مطمئن ہو مگر اس کے رشتہ داروں کو تکلیف ہو.دوست مصائب میں مبتلا ہوں یا ملک میں بد امنی رونما ہو.تب بھی انسان تکلیف محسوس کرتا ہے اور اگر رشتہ دار اور دوست تو آرام میں ہوں لیکن اس کا اپنا جسم بیمار ہو تب بھی اسے اطمینان نہیں ہو سکتا.تکمیل سعادت اسی وقت ہو سکتی ہے جب تینوں قسم کی سعادت یعنی سعادت نفسیہ، سعادت بدنیہ اور سعادت خارجیہ اسے حاصل ہو.اسی طرح شقاوت کی بھی تین قسمیں ہیں.پھر وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں بھی شقاوت اخرویہ اور شقاوت دنیویہ
Page 95
دونوں کے متعلق آیات پائی جاتی ہیں.اخروی شقاوت کا ذکر اس آیت میں ہے فَلَا يَضِلُّ وَ لَا يَشْقٰى(طٰہٰ: ۱۲۴) کہ وہ گمراہ نہیں ہو گا اور نہ شقی ہو گا.یہاں لَا يَشْقٰى سے مراد یہ ہے کہ اس کی روح شقاوت میں مبتلا نہیں ہو گی.اس کے مقابلہ میں دنیوی شقاوت کا ذکر اس آیت میں کیا گیا ہے کہ فَلَا یُخْرِجَنَّکُمَا مِنَ الْجَنَّۃِ فَتَشْقٰى (طٰہٰ: ۱۱۸) یعنی اے آدمؑ ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں جنت سے نکال دے اور تم شقی ہو جاؤ.یہاں شقاوت سے اخروی شقاوت مراد نہیں ہو سکتی.کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے.اس آیت میں فَتَشْقٰى کے معنے صرف یہ ہیں کہ تم جسمانی طور پر تکلیف میں مبتلا ہو جاؤ گے.بعض لغت والے بھی یہ لکھتے ہیں کہ کبھی تھکان کے معنوں میں بھی شقاوت کا لفظ استعمال کر لیا جاتا ہے جیسے کہتے ہیں شَقَیْتُ فِیْ کَذَا میں فلاں معاملہ میں پڑ کر سخت تھک گیا ہوں.مگر وہ کہتے ہیں اس میں ایک فرق بھی ہے کہ کُلُّ شَقَاوَۃٍ تَعَبٌ وَّلَیْسَ کُلُّ تَعَبٍ شَقَاوَۃً ہر شقاوت تعب کہلا سکتی ہے لیکن ہر تعب کو شقاوت نہیں کہا جاسکتا.کیونکہ شقاوت میں تذلیل کا ایک رنگ پایا جاتا ہے جو تعب میں نہیں ہوتا.اگر ایک خالص نیک کام کرتے ہوئے انسان کو تھکا ن ہو جائے تو اسے شقاوت نہیں کہا جائے گا.اگر ایک شخص پچھلی رات کو اٹھ کر دو تین گھنٹے تہجد کی نماز پڑھتا ہے تو لازمًا اسے تعب ہو جائے گی مگر اس تعب کو ہم شقاوت نہیں کہیں گے.شقاوت کا لفظ اس تعب کے متعلق استعمال کیا جاتا ہے جس میں بُرائی پائی جاتی ہو.پس اَشْقٰی اس کو کہیں گے جس میں شقاوت حد درجہ کی پائی جائے.تفسیر.اوپر کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون بیان فرمایا تھا کہ نصیحت کو بالالتزام جاری رکھنا چاہیے.کیونکہ خشیت کے اوقات انسانی قلب پر آتے رہتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ جو شخص آج انکار کر رہا ہو وہ کل ہماری باتوں کو تسلیم کرنے لگ جائے.اس آیت میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ اگر تم ہمارے اس حکم پر عمل جاری رکھو تو پھر ایسا ہی شخص ہدایت پانے سے محروم رہ سکتا ہے جو سخت شقی ہو اور جس کے گناہوں کی وجہ سے خدا تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا ہو کہ اب اسے ہدایت نہیں مل سکتی ورنہ اور لوگ ضرور مان جائیں گے.یہ علیحدہ سوال ہے کہ وہ جلدی مانتے ہیں یا دیر کے بعد مانتے ہیں.وَ يَتَجَنَّبُهَا الْاَشْقَى میں اَشْقٰی کا لفظ استعمال کرنے کی وجہ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اَشْقٰی کا لفظ کیوں استعمال فرمایا ہے.اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاؑء سے افضل ہیں اس لئے آپؐکا منکر بھی تمام انبیاؑء کے منکرین میں سے زیادہ شقی اور بدبخت ہے.موسٰی کا منکر
Page 96
صرف شقی ہے.عیسٰیؑ کا منکر صرف شقی ہے.ابراہیمؑ کا منکر صرف شقی ہے.داؤدؑ اور سلیمانؑ کا منکر صرف شقی ہے مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر اَشْقٰی ہے.کیونکہ آپؐتمام انبیاء سابقین سے زیادہ بلند درجہ رکھنے والے ہیں اور آپؐ جو ہدایت لائے وہ بھی تمام ہدایتوں سے افضل اور بلند تر ہے.دوسرے اَشْقٰی کا لفظ جیسا کہ میں اوپر بیان کر چکا ہوں یہ بتانے کے لئے بھی استعمال کیا گیا ہے.کہ ہدایت سے محروم صرف بڑا شقی ہوتا ہے ورنہ عا م شقی بھی کسی وقت ہدایت پاجاتا ہے.الَّذِيْ يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرٰى ۚ۰۰۱۳ (وہی) جو بڑی آگ میں داخل ہونے والا ہے.حلّ لُغات.یَصْلٰی.یَصْلٰی صَلٰی سے مضارع کا صیغہ ہے.اور صَلِیَ النَّارَ کے معنے ہوتے ہیں قَاسَی حَرَّھَا وَاِحْتَرَقَ بِـھَا وَدَخَلَ فِیْـھَا.یعنی آگ کی گرمی کی تکلیف برداشت کی اور آگ میں جلا اور اس میں داخل ہوا (اقرب) پس یَصْلَی النَّارَ کے معنے ہوں گے وہ آگ میں داخل ہو گا.تفسیر.چونکہ اس شخص نے سب سے بڑے نبی کا انکار کیا تھا اس لئے اس مناسبت کی بنا پر فرمایا کہ ایسے شخص کو سب سے بڑی آگ میں داخل کیا جائے گا یا باوجود بار بار کی اور پوری تبلیغ کے نہ مانا اس لئے اشد تریں بھڑکنے والی آگ میں داخل کیا جائے گا.ثُمَّ لَا يَمُوْتُ فِيْهَا وَ لَا يَحْيٰى ؕ۰۰۱۴ پھر (اس میں داخل ہونے کے بعد) نہ تو وہ اس میں مرے گا اور نہ زندہ رہے گا.تفسیر.وہ مرے گا اس لئے نہیں کہ زندہ رہے گا اور زندہ اس لئے نہیں ہو گا کہ زندگی اس کو کہتے ہیں جس میں اطمینان اور آرام اور سکون حاصل ہو.اسے چونکہ انتہائی تکلیف ہو گی اس لئے اس کے زندہ ہونے کو زندگی نہیں کہا جائے گا.اس کی ایسی ہی مثال ہے جیسے کسی سخت بیمار سے دریافت کیا جائے کہ تمہارا کیا حال ہے تو وہ کہتا ہے میرا حال کیا پوچھتے ہو میں نہ مرتا ہوں نہ جیتا ہوں.یعنی میں مرا تو نہیں کیونکہ جی رہا ہوں مگر میں جیتا بھی نہیں ہوں کیونکہ زندگی سخت تکلیف سے کٹ رہی ہے.اسی طرح فرماتا ہے لَا يَمُوْتُ فِيْهَا وَ لَا يَحْيٰى عذاب
Page 97
اتنا شدید ہو گا کہ نہ تو وہ مر کر اس سے چھٹکارا حاصل کر سکیں گے اور نہ زندہ رہ کر اس کو برداشت کرنے کی طاقت رکھیں گے ان کی زندگی موت سے بدتر ہو گی اس آیت میں ایک لطیفہ بھی ہے.عیسائی عام طور پر اعتراض کیا کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمنوں کو تلوار کے گھاٹ اتار دیا کرتے تھے ان کے اس اعتراض کا اس آیت سے بھی ردّ ہوتا ہے کیونکہ اس میں بطور پیشگوئی بتایا گیا ہے کہ اسلام کے دشمن جو آج تمہیں دکھائی دے رہے ہیں ان کو زندہ رکھا جائے گا تاکہ یہ اپنی آنکھوں سے اسلام کی ترقی اور اپنی ناکامی و نامرادی کو دیکھ دیکھ کر جلیں اور انہیں معلوم ہو کہ وہ کیسے غلط راستہ پر چلتے رہے ہیں.اگر مسلمان دشمنوں کو ہلاک کر دیتے تو یہ پیشگوئی کس طرح پوری ہوتی.پس دشمن کے اعتراض کا اس آیت میں جواب دے دیا گیا ہے.یہ سورۃ ابتدائی مکی سورتوں میں سے ہے اور شروع میں ہی مسلمانوں کو حکم دے دیا گیا ہے کہ تمہاری مخالفت تو ہو گی مگر دیکھنا دشمن کو مارنا نہیں سوائے اس کے کہ وہ خود حملہ کر کے آ جائیں کیونکہ ہم نے اسلام کو اتنی ترقی اور اتنی عظمت دینی ہے کہ ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہزار ہزار موت کے برابر ہو جائے گا پس انہیں زندہ رہنے دینا تاکہ یہ اسلام کی شوکت اور اپنی نامرادی کو دیکھ دیکھ کر ذلیل ہوں اور انہیں اپنی زندگی موت سے بھی بدتر معلوم ہو.قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى ۙ۰۰۱۵ جو پاک بنے گا وہ یقیناً کامیاب ہو گا.حلّ لُغات.اَفْلَحَ.اَفْلَحَکے معنے ہوتے ہیں فَازَ وَظَفِرَ بِـمَا طَلَبَ یعنی اپنے ارادہ میں کامیاب ہو گیا اور مقصود کو پا لیا.کہتے ہیں اَفْلَحَ زَیْدٌ اور معنے ہوتے ہیں نَـجَحَ فِی سَعْیِہٖ وَاَصَابَ فِیْ عَـمَلِہٖ زید نے اپنی کوشش کے پھل کو پا لیا اور اس کی محنت بار آور ہوئی (اقرب) تاج العروس میں ہے ہرشخص جو کسی دنیوی یا دینی بھلائی کو حاصل کر لے مُفْلِحٌ کہلاتا ہے اور فَلَاحٌ ایسی کامیابی کو کہتے ہیں جس پر دوسرے رشک کریں.ائمہ عرب کا اس پر اتفاق ہے کہ عربی زبان میں فَلَاحٌ کے لفظ سے بڑھ کر دینی اور دنیوی دونوں بھلائیوں کو شامل رکھنے والا لفظ اور کوئی نہیں(تاج العروس).تَزَکّٰی کے معنے ہیں صَارَ زَکِیًّا وہ پاک ہو گیا (اقرب) تفسیر.فرماتا ہے یقیناً وہ شخص بامراد ہوا جو نفسانی خواہشات سے اجتناب اختیار کر کے پاک ہوا.
Page 98
تَزَکّٰی کے معنے پاک ہونے کے ہوتے ہیں.پس اس آیت کے یہ معنے ہیں کہ وہ شخص کامیاب ہوا جس نے تقدس کا جامہ پہن لیا.اللہ تعالیٰ چونکہ خود قدوس ہے اس لئے وہی شخص اس کا قرب حاصل کر سکتا ہے جو تقدس اور پاکیزگی اپنے اندر پیدا کرتا ہے.گناہ آلود زندگی بسر کرنے والے خدا تعالیٰ کے احکام کو پس پشت ڈالنے والے شیطانی راہوں کو اختیار کرنے والے اور نفسانی خواہشات کے پیچھے چلنے والے دنیا میں بھی ذلیل ہوتے ہیں اور آخر ت میں بھی ذلیل ہوں گے.تمام کامیابیوں کی جڑ پاکیزگی اختیار کرنا ہے.وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰىؕ۰۰۱۶ اور (پاک بننے کے ساتھ ساتھ) اس نے اپنے رب کا نام لیا اور نماز پڑھتا رہا.تفسیر.ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ کے معنے صرف یہی نہیں کہ انسان منہ سے کہتا رہے کہ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ.سُبْحَانَ اللّٰہِ.اَللّٰہُ اَکْبَرُ.یا آج کل کے نام نہاد مسلمانوں کی طرح جو ذکر الٰہی کی اہمیت اور اس کے طریق سے ناواقف ہوتے ہیں صرف اللہ اللہ کہتا رہے بلکہ اس کے معنے یہ ہیں کہ خدا انسان کو ہر وقت یاد رہے چنانچہ فَصَلّٰى کا لفظ جو اس کے ساتھ ہی استعمال ہوا ہے بتا رہا ہے کہ ذَكَرَ سے مراد محض الفاظ کی رٹ لگانا نہیں بلکہ اس سے مراد وہ ذکر ہے جس کے نتیجہ میں نماز پڑھی جاتی ہے اگر منہ سے کہنے والی بات ہی مراد ہوتی تو وہ تو خود بخود نماز میں آجاتی ہے اس کے علیحدہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی مگر اللہ تعالیٰ کا ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ کا پہلے ذکر کرنا اور فَصَلّٰى کو بعد میں رکھنا بتا رہا ہے کہ یہ وہ ذکر ہے کہ جس کے بعد نماز پڑھی جاتی ہے یعنی انسانی قلب پر خدا تعالیٰ کی محبت اس قدر غالب ہو کہ وہ بے چین ہو کر کھڑا ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جائے.پھر خدا کی محبت کا شعلہ اس کے دل میں بھڑک اٹھے اور وہ اپنے محبوب کے سامنے سربسجود ہو جائے گویا ایک دیوانگی اور وارفتگی اس پر طاری ہو.خدا تعالیٰ کا ذکر اس کی غذا ہو اور اس کی یاد اس کے دل میں اس طرح بار بار تازہ ہو کہ وہ اس بات پر مجبور ہو جائے کہ خدا تعالیٰ کی عبادت کرے اور اپنی محبت کے جذبات کا ہدیہ اس کے سامنے پیش کرے.گویا اس ذَكَرَ سے مراد محض منہ سے اللہ تعالیٰ کہنا نہیں بلکہ وہ عملی حالت مراد ہے جو اللہ تعالیٰ کے عشق پر دلالت کرتی ہے اور جس کے نتیجہ میں نماز اور عبادت پیدا ہوتی ہے.
Page 99
بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَاٞۖ۰۰۱۷ مگر (اے مخالفو) تم (لوگ) تو ورلی زندگی کو (آخرت پر) ترجیح دیتے ہو.وَ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّ اَبْقٰى ؕ۰۰۱۸ حالانکہ آخرت کہیں بہتر اور دیرپا ہے.حلّ لُغات.تُؤْثِرُوْنَ.تُؤْثِرُوْنَ اٰثَرَ سے مضارع جمع مخاطب کا صیغہ ہے اور اٰثَرَ کے معنے ہیں کسی چیز کو عمدہ سمجھ کر اختیار کرلیا یا کسی ایک چیز کو دوسری پر فضیلت دی (اقرب) پس تُؤْثِرُوْنَ کے معنے ہوں گے تم ترجیح دیتے ہو (۲)عمدہ سمجھ کر اختیار کرتے ہو.تفسیر.اس آیت میں اللہ تعالیٰ دشمنانِ اسلام کی مخالفت کی وجہ بیان کرتا ہے کہ ان کی یہ مخالفت کسی نیک جذبہ کی بنا پر نہیں کیونکہ مسلمان تو خدا تعالیٰ سے محبت کرنے والے اور اس کی عبادتیں کرنے والے ہیں بلکہ اس لئے ہے کہ وہ دنیوی زندگی کو اخروی زندگی پر ترجیح دیتے ہیں سو مسلمانوں کو اپنے لئے سدراہ سمجھتے ہیں حالانکہ وہ نادان اتنا نہیںجانتے کہ دنیوی حیات تو ایک عارضی چیز ہے باقی رہنے والی زندگی تو وہی ہے جو آخرت کی ہے.مگر چونکہ آخرت پر ان کو ایمان نہیں اور دنیوی زندگی کے وہ دلدادہ ہیں اس لئے مسلمانوں کی مخالفت کرتے ہیں.اِنَّ هٰذَا لَفِي الصُّحُفِ الْاُوْلٰى ۙ۰۰۱۹ یقیناً یہی (بات) پہلے صحیفوں میں بھی (درج) ہے.صُحُفِ اِبْرٰهِيْمَ وَ مُوْسٰىؒ۰۰۲۰ (یعنی) ابراہیم اور موسٰی کے صحیفوں میں.تفسیر.فرماتا ہے یہ بات جو ہم نے پہلے بیان کی ہے یہ کوئی فرضی اور من گھڑت نہیں بلکہ صحف اولیٰ میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے چنانچہ موسٰی اور ابراہیم ؑکے صحف کا مطالعہ کرو تو تمہیں معلوم ہو گا کہ ان صحف میں
Page 100
ایک قولِ فصل کی خبر دی گئی تھی اور بتایا گیا تھا کہ ایک بہت بڑا نبی آنے والا ہے جو اپنے ساتھ ایک کامل شریعت لائے گا.ان صحف میں اس قسم کی پیشگوئیوں کا موجود ہونا بتا رہا ہے کہ باوجود پہلی کتب کے اس کتاب کی ضرورت تھی تبھی تو پہلے نبیوں نے اس کی خبر دی ورنہ انہیں اپنے بعد کسی اور نبی کے مبعوث ہونے یا کسی اور کتاب کے نازل ہونے کی خبر دینے کی کیا ضرورت تھی.صحف ابراہیمؑ وموسٰی میں آنحضرتؐکے متعلق پیشگوئیاں صحف ابراہیمؑ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی جو خبر دی گئی تھی اس کو خود قرآن کریم نے نقل کیا ہے.چنانچہ فرماتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ رَبَّنَا وَ ابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمْ١ؕ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ (البقرۃ:۱۳۰) یعنی اے میرے رب تو ان میں ایک ایسا رسول مبعوث کیجیو جو ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے انہیں کتاب اور حکمت سکھائے اور انہیں پاکیزہ و مطہر بنائے.اگر ابراہیمؑ کے صحف ہی قولِ فصل ہوتے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کیوں کرتے.ان کی اس دعا سے صاف پتہ لگتا ہے کہ خواہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نوحؑ کی شریعت پر عمل کرنے والے تھے جیسا کہ اِنَّ مِنْ شِيْعَتِهٖ لَاِبْرٰهِيْمَ (الصّٰفّٰت :۸۴) سے ثابت ہے اور خواہ ان کے اپنے الہامات کے بعض صحف تھے.بہرحال ان کی تعلیمیں مٹنے والی تھیں اگر مٹنے والی نہ ہوتیں تو وہ یہ دعا ہی کیوں کرتے.یہی حال حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے ان کی کتاب تورات میں تو نہایت صراحت کے ساتھ یہ پیشگوئی آج تک موجود ہے کہ ’’میں ان کے لئے ان کے بھائیوں میں سے تجھ سا ایک نبی برپا کروں گا اور اپنی کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا اور جو کچھ میں اسے فرماؤں گا وہ سب ان سے کہے گا اور ایسا ہو گا کہ جو کوئی میری باتوں کو جنہیں وہ میرا نام لے کر کہے گا نہ سنے گا تو میں اس کا حساب اس سے لوں گا.‘‘ (استثناء باب ۱۸آیت ۱۸،۱۹) اسی طرح استثناء باب ۳۳ آیت ۲میں لکھا ہے ’’خداوند سینا سے آیا اور شعیر سے ان پر طلوع ہوا.فاران ہی کے پہاڑ سے وہ جلوہ گر ہوا.دس ہزار قدوسیوں کے ساتھ آیا اور اس کے داہنے ہاتھ ایک آتشی شریعت ان کے لئے تھی.‘‘ (استثناء باب ۳۳ آیت ۱تا۳) پس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے بعد ایک شرعی نبی کے آنے کی خبر دی ہے اور بتایا ہے کہ وہ نبی بنی اسرائیل میں سے نہیں آئے گا بلکہ ان کے بھائیوں بنی اسماعیل میں سے آئے گا.گویا ابراہیمؑ بھی ایک شرعی نبی کی خبر دیتے ہیں اور موسٰی بھی ایک شرعی نبی کی خبر دیتے ہیں جس کے صاف معنے یہ ہیں کہ پہلے احکام قولِ فصل نہیں تھے قولِ فصل ابھی آنے والا تھا جس کی اللہ تعالیٰ کے کئی انبیاؑء یکے بعد دیگرے خبر دیتے چلے آئے تھے.اس قسم کی
Page 101
اور بھی کئی پیشگوئیاں بائیبل میں پائی جاتی ہیں اور ان سے یہ واضح ہوتا ہے کہ قولِ فصل کا دنیا کو ایک مدت سے وعدہ دیا جا رہا تھا اور ضروری تھا کہ اب اس وعدہ کو پورا کر دیا جاتا.حضرت موسیٰعلیہ السلام کی پیشگوئی کا تو تورات میں آج تک ذکر موجود ہے مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشگوئی کا تورات میںکہیں وضاحت کے ساتھ ذکر نہیں آتا صرف قرآ ن کریم نے اس کا ذکر کیا ہے لیکن قرآن کریم کے اس دعویٰ کی صداقت کا ثبوت یہ ہے کہ مکہ کے لوگوں کے سامنے قرآن کریم نے یہ بات پیش کی اور بڑے زور سے اعلان کیا کہ قرآن کے متعلق صحف ابراہیمؑ اور صحف موسٰی میں پیشگوئی پائی جاتی ہے.مگر کفار میں سے کسی نے بھی اس کا انکار نہ کیا اور انہوں نے ایک دفعہ بھی یہ اعتراض نہیں کیا کہ تم غلط کہتے ہو صحف ابراہیمؑ میں اس قسم کی کوئی پیشگوئی نہیں.جس سے معلوم ہوتا ہے کہ لاکھوں لوگوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس پیشگوئی کا علم تھا اور وہ جانتے تھے کہ ابراہیمؑ نے یہ پیشگوئی کی ہوئی ہے کہ میرے بعد ایک شرعی نبی آئے گا.یہی وجہ ہے کہ وہ خاموش رہے.ورنہ وہ کفار جو بات بات پر اعتراض کرنے کے عادی تھے اتنی اہم بات پر کس طرح خاموش رہ سکتے تھے.خود قرآن کریم نے کفار کے کئی اعتراضات کو نقل کیا ہے مگر کہیں بھی ان کے اس اعتراض کا ذکر نہیں آتا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف ایک غلط بات منسوب کر دی گئی ہے.انہوں نے کوئی پیشگوئی قرآن کے متعلق یا اپنے بعد کسی شرعی نبی کے آنے کے متعلق نہیں کی تھی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ عرب میں کثرت سے یہ پیشگوئیاں رائج تھیں اور لوگوں کو امید تھی کہ اب ان پیشگوئیوں کے مطابق ضرور کوئی نہ کوئی شخص ظاہر ہو گا چنانچہ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ عربوں میں سے بعض لوگوں نے اپنے بچوں کا نام محمد رکھنا شروع کر دیا تھا کیونکہ تورات کی پیشگوئیوں سے انہیں معلوم ہو چکا تھا کہ آنے والے کا نام محمد ہو گا اس بنا پر انہوں نے اپنے بچوں کا نام محمد رکھنا شروع کر دیا کہ شائد ہمارا بچہ ہی نبی بن جائے اور ان پیشگوئیوں کا مصداق ہو جائے.غرض آنے والے موعود کے متعلق عربوں کے دلوں میں امیدیں پائی جاتی تھیں اور وہ اس بات کے منتظر تھے کہ کب ان پیشگوئیوں کا مصداق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظاہر ہوتا ہے.
Page 102
سُوْرَۃُ الْغَاشِیَۃِ مَکِّیَّۃٌ سورۃ غاشیہ.یہ سورۃ مکی ہے وَھِیَ سِتٌّ وَّعِشْـرُوْنَ اٰیَۃً دُوْنَ الْبَسْمَلَۃِ وَ فِیْـھَا رُکُوْعٌ وَّاحِدٌ اور اس کی بسم اللہ کے علاوہ چھبیس آیات ہیں اور ایک رکوع ہے سورۃ غاشیہ مکی سورۃ ہے اس سورۃ کا نام غاشیہ ہے اور یہ سورۃ بغیر کسی اختلاف کے مکی ہے.حضرت عبداللہ بن عباسؓ اور حضرت عبداللہ بن زبیرؓ دونوں سے مروی ہے کہ یہ سورۃ مکہ میں نازل ہوئی تھی اور چونکہ کوئی اور روایت اس کے خلاف نہیں اس لئے اس سورۃ کے مکی ہونے میں کوئی شبہ نہیں.مسند احمد بن حنبل اور مسلم اور سنن نسائی اور سنن ابوداؤد اور ابن ماجہ میں نعمان بن بشیرؓ سے روایت آتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ اور عیدین کی پہلی رکعت میں سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى اور دوسر ی میں سورۃ الغاشیہ پڑھا کرتے تھے بلکہ اگر دونوں نمازیں جمع ہو جاتی تھیںیعنی اگرکبھی عیدالفطر اور جمعہ اکٹھے ہو جاتے یا عیدا لاضحیہ اور جمعہ اکٹھے ہو جاتے تب بھی آپ دونوں نمازوں میں یہ دونوں سورتیں پڑھا کرتے تھے.(صحیح مسلم کتاب الجمہ، باب ما یقرأ فی صلاۃ الجمعۃ ) زمانہ نزول پادری ویری لکھتے ہیں کہ اس سورۃ کے نزول کا زمانہ چوتھے سال نبوت کے قریب ہے کیونکہ اس کے مضامین ایسے ہیں جن سے پتہ لگتا ہے کہ مسلمانوں پر کفار کے مظالم یا تو شروع ہو گئے تھے یا شروع ہونے والے تھے.(A Comprehensive Comentary on Quran by Wherry vol:4 p239) نولڈکے NOLDEKE جو جرمن مصنّف ہے اس کا بھی یہی خیال ہےاور چونکہ صحابہؓ کی رائے بھی جو قطعی طور پر آپس میں ملتی ہے اس رائے کے موافق ہے جس کے معنے یہ ہیں کہ یہ سورۃ اتنا عرصہ پہلے نازل ہوئی ہے کہ یہ خیال بھی نہیں کیا جا سکتا کہ اس کے ابتدائی زمانہ میں نازل ہونے کے خلاف کوئی بات کہی جا سکتی ہو اس لئے ہمیں اس سورۃ کے متعلق کسی بات کی تردید کی ضرورت ہی نہیں پڑتی.اس کے مضامین ایسے ہی ہیں جن سے پتہ لگتا ہے کہ دشمن اپنی دشمنی کو شروع کرنے والا ہے.اس میں ایسی
Page 103
دشمنی کا اظہار نہیں جو عملًا رونما ہو چکی ہو لیکن اتنا ضرور معلوم ہوتا ہے کہ لوگ منصوبہ بازیاں کر رہے ہیں تاکہ مسلمانوں پر سختی کریں اور مسلمان حیران ہیں کہ اب ہمارا کیا بنے گا.پس یوروپین مصنّفین کا استدلال غلط نہیں کہ یہ سورۃ ابتدائی زمانہ کی ہے بلکہ اسلامی روایات کے مطابق درست ہی معلوم ہوتا ہے.سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ غاشیہ کا اسلام کی اجتماعی زندگی کے ساتھ گہرا تعلق اس سورۃ اور سورۃ الاعلیٰ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جمعہ اور عیدین میں پڑھنا اور بالالتزام پڑھنا اور اتنا تعہد کرنا کہ اگر دونوں نمازیںجمع ہو جائیں تب بھی آپ دونوں میں التزامًا یہ سورتیں پڑھا کرتے تھے بتاتا ہے کہ اسلام کی اجتماعی زندگی کے ساتھ یہ دونوں سورتیں گہرا تعلق رکھتی ہیں.سورۃ الاعلیٰ کا جوڑ تو نظر ہی آتا ہے کہ اس میں قرآن کریم کے قولِ فصل ہونے کے لحاظ سے بحث کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ کس طرح اسلام اپنے انتہائی کمال کو پہنچ جائے گا.اس ضمن میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اسلام کو ایسے خادم مل جا ئیں گے جو قرآن کریم کے حافظ ہوں گے.اسی طرح اس کی حفاظت کے متعلق اور کئی قسم کی غیر معمولی تحریکات دنیا میں جاری ہو جائیں گی.گویا سورۃ الاعلیٰ اسلامی ترقی اور دین اسلام کی اشاعت اس کے ماننے والوں کی زیادتی اور مسلمانوں کے غلبہ پر دلالت کرتی تھی اور سورۃ الغاشیہ میں گو وہ مضمون نہیں مگر اس میں بھی یہ بات ضرور پائی جاتی ہے کہ کافروں کے اسلام کے خلاف اٹھنے اور زور لگانے کا اس میں اشارہ کیا گیا ہے اور مومنوں کا ان کے مقابلہ میں کامیاب ہونا اشارۃً بیان کیا گیا ہے مگر چونکہ ابھی اسلام کے ابتدائی ایام تھے اور خواہ مخواہ کفار کو بھڑکانہ مقصود نہیں تھا اس لئے جنگ اور مقابلے کا اللہ تعالیٰ صریح الفاظ میں ذکر نہیں کرتا بلکہ ایسے الفاظ میں ذکر کرتا ہے جو ٹھیس لگانے والے نہ ہوں.جس طرح دشمن نے کھلے طور پر مخالفت کا اظہار نہیں کیا تھا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی کھلے طور پر یہ ذکر نہیں کیا کہ مسلمان لڑیں گے اور کفار کو مغلوب کرلیں گے صرف نتیجے کا ذکر کر دیا ہے کہ اسلام کے خلاف مخالفین کچھ کوششیں کریں گے لیکن وہ اسلام کو گزند پہنچانے میں ناکام رہیں گے اور آخر مسلمانوں کو اپنے مخالفین پر غلبہ حاصل ہو جائے گا.گویا صاف الفاظ میں اس سورۃ میں لڑائی کا ذکر نہیں کیا صرف اشارۃً اس کا ذکر کیا ہے تاکہ اس وقت جب کہ مخالفین اسلام نے کھلے طور پر حملہ نہیں کیا تھا اس قسم کی باتوں کی وجہ سے اسلام کی طرف سے ابتدا نہ سمجھی جائے اور یہ خیال نہ کیا جائے کہ کفار کو انہوں نے بھڑکا دیا ہے.سورۃ کا خلاصہ مضمون اس سورۃ کا مضمون بھی اجتماعی کاموں پر دلالت کرتا ہے.چنانچہ اس سورۃ میں ایک مجموعۂ افراد کا ذکر کرتے ہوئے پیشگوئی کی گئی ہے کہ وُجُوْهٌ يَّوْمَىِٕذٍ نَّاعِمَةٌ لِّسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ.ان الفاظ میں
Page 104
اللہ تعالیٰ نے صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترقی کی خبر نہیں دی بلکہ جماعت مسلمہ کی ترقی کی بھی خبر دی ہے اسی طرح وُجُوْہٌ يَّوْمَىِٕذٍ خَاشِعَۃٌ عَامِلَۃٌ نَّاصِبَۃٌ میں اجتماعی طور پر کفار کے متعلق خبر دی گئی ہے کہ وہ مسلمانوں کے مقابلہ میں ناکام رہیں گے.حقیقت یہ ہے کہ جس طرح سورۃ الاعلیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اور آخری زمانہ یعنی ہر دو زمانوں کے متعلق ہے اور یہ سورۃ بھی ان دونوں زمانوں کے حالات بیان کرتی ہے.چونکہ ان دونوں سورتوں کا مضمون ایسا ہے جو شروع زمانۂ اسلام سے آخر زمانۂ اسلام تک تعلق رکھنے والا تھا.اس لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جمعہ اور عیدین میں بالالتزام ان دونوں سورتوں کی تلاوت فرمایا کرتے تھے.جمعہ اور عیدین جو اجتماع کے مواقع ہیں ان میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان دونوں سورتوں کی تلاوت کرنا بتاتا ہے کہ جب بھی مسلمان اجتماعی طاقت پکڑنے کی طرف متوجہ ہوں گے اور جب بھی خدا تعالیٰ مسلمانوں کی کمزوری کو دور کرنے لگے گا اس وقت یہ دونوں سورتیں اپنے مطالب کے لحاظ سے ظاہر ہو جائیں گی.سورۃ الاعلیٰ میں یہ بات واضح کی گئی تھی کہ مسلمانوں کی ترقی اسی وقت ہو گی جب قرآن کریم کے معارف اور اس کے علوم کو ظاہر کرنے والا مامور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گا.گویا مسلمانوں کی ترقی کبھی بھی دنیوی ذرائع سے نہیں ہو گی بلکہ مامورین پر ایمان لانے اور ان کی ہدایات پر چلنے کے ذریعہ ہو گی جیسا کہ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسٰۤى کے الفاظ اس پر شاہد ہیں کہ قرآن کریم کے خدام جو بھولے ہوئے قرآن کو پھر واپس لائیں گے ان کے ذریعہ ہی مسلمان اپنی کھوئی ہوئی عزت کو حاصل کر سکیں گے.آج جو مسلمان سیاسی ذرائع سے ترقی حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کو سورۃ الاعلیٰ کے مضامین کی طرف توجہ کرنی چاہیے.اسلام کی ترقی تلواروں کے سایہ کے نیچے اب اس سورۃ میں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جب بھی اسلام کو ترقی ہو گی تلواروں کے سایہ کے نیچے ہو گی.کبھی کوئی مامور ایسا نہیں آ سکتا جس کے آنے پر دنیا اس کا خوشی سے استقبال کرے اور کہے کہ ’’جی آئیاں نوں‘‘ یا ’’بھلے آئے‘‘ یا ’’برسروچشم‘‘ بلکہ جب بھی کوئی مامور آئے گا وُجُوْهٌ يَّوْمَىِٕذٍ خَاشِعَةٌ عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ کی حالت رونما ہو گی اور ضرور اس کی مخالفت ہو گی اس مخالفت کے بغیر کسی روحانی سلسلہ کی ترقی کا امکان بالکل ناممکن ہے.اگر حضرت مسیح ناصریؑ جیسا کہ مسلمان سمجھتے ہیں کسی وقت آسمان سے اتر آئیں تو ان کے زمانہ میں وُجُوْهٌ يَّوْمَىِٕذٍ خَاشِعَةٌ عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ کی کوئی صورت نہیں ہو سکتی.لوگ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جائیں گے اور ان کے حلقۂ غلامی میں شامل ہو جائیں گے کیونکہ فرشتے ان کے ساتھ ہوں گے اور کسی کو انکار کی جرأت نہیں ہو سکے گی.مگر الٰہی سنت کے ماتحت ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ضروری ہے کہ ہر الٰہی سلسلہ کی
Page 105
مخالفت ہو اور مخالفت کے بعد اس کو ترقی نصیب ہو.غرض ان دونوں سورتوں سے پتہ لگتا ہے کہ اسلام کو ہمیشہ شدید مخالفت کے بعد ترقی ہوتی ہے پس یہ دونوں سورتیں مضامین کے لحاظ سے آپس میں گہرا تعلق رکھتی ہیں.سورۃ غاشیہ کا سورۃ الاعلیٰ سے تعلق اس سورۃ کا سورۃ الاعلیٰ سے ایک قریبی تعلق بھی ہے جو بحر محیط کے مصنّف نے بیان کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ پہلی سورۃ میں نار اور آخرت سے ڈرانے کا حکم تھا اور اس سورۃ میں دوزخ و جنت کا ذکر کیا گیا ہے مگر اصل تعلق وہی ہے جو میں نے بیان کیا ہے کہ ان ہر دو سورتوں میں اسلام کی ترقی کے دو۲ اصول بیان کئے گئے ہیں.سورۃ الاعلیٰ میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب بھی مسلمانوں کا تنزّل ہو گا قرآن کریم کے بھولنے سے ہو گا اور جب بھی مسلمانوں کی ترقی ہو گی ایسے شخص کے ذریعہ ہو گی جو قرآن کو آسمان سے واپس لائے گا گویا ایسے مامور تو آئیں گے جو بھولے ہوئے قرآن کو یاد کرائیں گے مگر ایسے مامور نہیں آ سکتے جو نئی شریعت لائیںاور سورۃ الغاشیہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ مسلمانوں کی ترقی دَور اوّل میں ہو یا دَور آخر میں ہمیشہ ایسے ماموروں کے ذریعہ ہو گی جن کی شدید مخالفت ہو گی مگر بالآخر وہ جیت جائیں گے جیسا کہ وُجُوْهٌ يَّوْمَىِٕذٍ خَاشِعَةٌ عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ میں بتایا ہے.پس مسلمانوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ ان کی ترقی ہمیشہ مامورین پر ایمان لانے اور ساری دنیا سے لڑائی جھگڑا مول لینے کے بعد ہو گی.ایسا وجود کوئی نہیں آ سکتا جسے لوگ آپ ہی آپ مان لیں.پس آسمان سے کسی مامور کے اترنے کا خیال بالکل خلاف قرآن ہے.بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۰۰۱ (میں) اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا (اور) بار بار رحم کرنے والا ہے (شروع کرتا ہوں) هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِؕ۰۰۲ کیا تجھے (دنیا پر) چھا جانے والی (مصیبت) کی بھی خبر پہنچی ہے؟ (یا نہیں).حلّ لُغات.ھَلْ.ھَلْ جب فعل سے پہلے آئے تو اس کے معنے قَدْ کے ہوتے ہیں لیکن عام طور پر ھَلْ تصدیق ایجابی کے لئے آتا ہے (مغنی اللبیب لابن ھشام) یعنی عام معنے اس کے ایسے سوال کے ہیں جس کے جواب میں تصدیق کا مطالبہ ہوتا ہے سوائے اس کے کہ اس کے بعد اِلَّا آ جائے اس وقت اس کے معنے نفی کے ہوجاتے ہیں.پس آیت کے معنے یا تو یہ ہوں گے کہ کیا حدیثِ غاشیہ آ پہنچی یا نہیں یعنی آ پہنچی ہے اور یا پھر یہ
Page 107
اور مسیح موعودؑ کے زمانہ کے لئے بھی اس کی پیشگوئی تھی.سورۂ دخان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَاْتِي السَّمَآءُ بِدُخَانٍ مُّبِيْنٍ.يَّغْشَى النَّاسَ١ؕ هٰذَا عَذَابٌ اَلِيْمٌ(الدّخان:۱۱،۱۲) یعنی تو انتظار کر اس دن کا جب آسمان پر دھواں ہی دھواں چھا جائے گا اور سارے انسانوں کو اپنے اندر ڈھانپ لے گا یہ عذاب ہے جو نہایت ہی دردناک ہو گا.غاشیہ سے مراد قحط کا عذاب چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم کو جب مکہ والوں نے سخت دکھ دیا تو آپ نے اس پیشگوئی کے ماتحت دعا کی کہ اَللّٰھُمَّ اَعِنِّیْ عَلَیْـھِمْ بِسَبْعٍ کَسَبْعِ یُوْسَفَ (صحیح بخاری کتاب التفسیر باب ’’ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَ قَالُوْا مُعَلَّمٌ مَّجْنُوْنٌ‘‘) اے خدا ان لوگوں نے مجھے سخت تنگ کر لیا ہے تو میری ان سات سالوں سے مدد فرما جن سات سالوں سے تو نے حضرت یوسف علیہ السلام کی مدد کی تھی چنانچہ اس دعا کے نتیجہ میں اس زمانہ میں شدید قحط پڑا.بارشیں رک گئیں اور اس قدر تباہی آئی کہ مکہ والوں نے ابو سفیان کو خاص طور پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا اور کہا کہ آ پ کی قوم قحط کی وجہ سے برباد ہو گئی آپ دعا کریں کہ ان کی یہ حالت بدل جائے (صحیح بخاری کتاب التفسیر باب ’’ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَ قَالُوْا مُعَلَّمٌ مَّجْنُوْنٌ‘‘) گویا جس طرح فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اپنے سفیر بھیجے تھے اسی طرح مکہ والوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کی خدمت میں اپنا سفیر بھیجا اور درخواست کی کہ اس قحط کے دور ہونے کے متعلق دعا فرمائی جائے چنانچہ آپ نے دعا کی اور اللہ نے اس قحط کو دور کر دیا.تو غاشیہ سے مراد وہ عذاب دخان بھی ہے جس کا ذکر سورۂ دخان میں کیا گیا ہے.اس دخانِ مبین کے عذاب کی مسیح موعودؑ کے زمانہ کے لئے بھی پیشگوئی کی گئی ہے چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر جو الہامات نازل ہوئے ان میں ایک الہام یہ بھی ہے کہ یَوْمَ تَاْتِی السَّمَآءُ بِدُخَانٍ مُّبِیْنٍ وَتَرَی الْاَرْضَ یَوْمَئِذٍ خَامِدَۃً مُّصْفَرَّۃً (تذکرہ :۵۰۴) حضرت مسیح موعودؑ کے زمانہ میں آپ کی پیشگوئی کے مطابق قحط کا عذاب غرض علاوہ اور عذابوں کے جن کی طرف حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے الہامات میں اشارہ کیا گیا ہے قحط کے عذاب کی خبر بھی آپ کے الہامات میں موجود ہے اور بتایا گیا ہے کہ اس زمانہ میں لوگوں پر شدید تنگی اور مصیبت کے سال آئیں گے.چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانہ میں علاوہ عام قحطوں کے جنگوں کی وجہ سے جو قحط پڑے ہیں وہ ایسے شدید ہیں کہ ان کی مثال پہلے زمانوں میں نہیں ملتی.دنیا میں ایک ایک سال کے قحط پڑتے ہیں تو تباہی آ جاتی ہے مگر یہاں قحطوں کی یہ حالت ہے کہ بعض اقوام ایسی ہیں جنہوں نے چھ چھ سال سے پیٹ بھر کر
Page 108
کھانا نہیں کھایا.۱۹۴۲ء کے شروع میں جب قحط کی تکلیف شروع ہوئی اور غلّہ کی سخت قلت ہو گئی تو میں ان دنوں میں سندھ میں تھا مجھے وہاں قادیان سے اطلاع ملی کہ یہاں اوّل تو گندم ملتی ہی نہیں اور اگر ملتی ہے تو اس کی روٹی کالی پکتی ہے چنانچہ میں نے جو گندم کا نمونہ دیکھا زیرہ کے برابر اس کا دانہ تھااور رنگ ایسا تھا جیسے سیاہ گڑ ہوتا ہے میرے نزدیک تو اس گندم سے پکی ہوئی روٹیاں جانوروں کے کھانے کے قابل بھی نہیں تھیں مگر لوگ ان ایام میں مجبوراً وہی کھاتے رہے.بنگال میں یہ حالت ہو گئی کہ ایک یتیم لڑکی جو ایک احمدی نے پرورش کے لئے رکھی ہوئی ہے بتاتی ہے کہ میں اور واقعات تو بھول گئی ہوں مگر مجھے اتنا یاد ہے کہ لوگ مردوں کی ہڈیاں لے کر کھا جاتے تھے.بعض جگہ پر ثابت ہوا ہے کہ عورتوں نے اپنے بچے ذبح کر کے کھا لئے.یہ کیسا خطرناک قحط ہے کہ دس لاکھ آدمی سے زیادہ چند مہینوں میں ہی بھوک کی وجہ سے مر گیا اور یہ دس لاکھ بھی گورنمنٹ کا اندازہ ہے ورنہ پبلک کا اندازہ یہ ہے کہ بنگال میں بیس لاکھ آدمی قحط کی وجہ سے ہلاک ہوئے ہیں حالانکہ بیس لاکھ آدمی جنگ کے قریبًا چھ سالہ عرصہ میں بھی ہلاک نہیں ہوئے.پھر یہ وہ زمانہ ہے جس میں ریل موجود ہے، موٹریں موجود ہیں، لاریاں موجود ہیں، نہریں چل رہی ہیں اور سامان خورد ونوش نہایت آسانی کے ساتھ ایک مقام سے دوسرے مقام پر پہنچایا جا سکتا ہے باوجود سامانوں کی اس قدر افراط کے ایک سال کے اندر اندر بیس لاکھ آدمی بنگال میں بھوک کی وجہ سے ہلاک ہوگئے.اگر یہ قحط کسی ایسی جگہ پڑتا جہاں کھانے پینے کا سامان کسی صورت میں بھی پہنچایا نہ جا سکتا تو شاید ایک آدمی بھی نہ بچتا اور سب کے سب ہلاک ہو جاتے.ہزارہا آدمی ایسے ہیں جو بنگال سے نکل کر پنجاب اور سرحد میں آبسے ہیں اور انہوں نے یہ خیال کر لیا ہے کہ اب شاید قیامت تک بنگال میں قحط ہی رہے گا.بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں سے کوئی زندہ ہی نہیں رہا اس لئے ہم گھبرا کر وہاں سے نکل آئے ہیں اب ہم نے واپس جا کر کیا کرنا ہے.بعض واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ ایک بھوک سے تڑپتے ہوئے بچہ کو اٹھا کر لایا گیا اور اسے دودھ پلایا گیا تو دودھ کے اندر جاتے ہی وہ بچہ ہلاک ہو گیا.دراصل لمبے فاقہ کی وجہ سے معدہ میں زہر پیدا ہو جاتا ہے اور جب دودھ یا کوئی اور غذا اندر جاتی ہے تو انسان ہلاک ہو جاتا ہے.پس هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ کے یہ معنے ہیں کہ کیا تمہیں معلوم ہے یا نہیں کہ غاشیہ کہلانے والی مصیبت بھی آنے والی ہے.هَلْ چونکہ عام طور پر تصدیق ایجابی کے لئے آتا ہے اس لئے اس کے معنے یہ ہوں گے کہ کیا حدیث غاشیہ آ پہنچی کہ نہیں یعنی آ پہنچی ہے.لیکن هَلْ جب فعل سے پہلے آئے تو کبھی قَدْ کے معنے بھی دیتا ہے اس لحاظ سے آیت یوں ہو گی قَدْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ لو اب مخالفتیں تیز ہونے والی ہیںاس لئے خدا تعالیٰ کی
Page 109
طرف سے بھی عذاب کی خبریں آ رہی ہیں یا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تیری طرف حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ بھیج دی.دشمن اب شرارت میں بڑھنے والا ہے اس لئے ہم نے بھی عذاب کی خبریں دینی شروع کر دی ہیں.هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ میں آنحضرت صلعم کی فتح کی خبر اور غاشیہ کے معنے چونکہ اس شخص کے بھی ہوتے ہیں جس کے پاس کثرت سے لوگ آئیں اس لئے حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ کے معنے فتوحات کے بھی ہو سکتے ہیں اور معنے یہ ہوں گے کہ چاروں طرف سے لوگوں کے وفود تیرے پاس آئیں گے.گویا درمیانی زمانۂ مخالفت کو چھوڑ دیا اور آخری نتیجہ بیان کر دیا کہ تیرے پاس وفود آئیں گے.ان معنوں کے لحاظ سے حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ میں سال وفود کی خبر دی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ کفار سے جنگ ہو گی.تو اس جنگ میں جیت جائے گا اور پھر چاروں طرف سے لوگوں کے وفود تیرے پاس آئیں گے دشمن ان کو دیکھ دیکھ کر جل مرے گا اور مومن بہت بڑی ترقیات حاصل کریں گے.وُجُوْهٌ يَّوْمَىِٕذٍ خَاشِعَةٌۙ۰۰۳ اس دن (جب وہ مصیبت چھا جائے گی) کچھ چہرے اترے ہوئے ہوں گے عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌۙ۰۰۴ (وہ) محنت کر رہے ہوں گے (اور) تھک کر چور ہو رہے ہوں گے(لیکن محنت انہیں فائدہ نہ دے گی).حلّ لُغات.وُجُوْهٌ.وُجُوْهٌ : وَجْہٌ کی جمع ہے اور وَجْہٌ کے اصل معنے تو چہرے کے ہوتے ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی اس کے کئی معنے ہوتے ہیں چنانچہ ایک معنے سَیِّدُ الْقَوْمِ کے ہوتے ہیں یعنی قوم کا سردار.پھر وَجْہٌ کے معنے اس انسان کے بھی ہوتے ہیں جو عزت اور وجاہت رکھتا ہو (اقرب) چنانچہ کہتے ہیں رَجُلٌ وَجْہٌ اور مراد ہوتی ہے ذُوْ جَاہٍ یعنی فلاں آدمی بڑی عزت اور وجاہت والا ہے پس وُجُوْهٌ کے معنے ہوئے کچھ لوگ جو معزز سمجھے جاتے ہیں یا کچھ لوگ جو قوم کے سردار ہیں.خَاشِعَۃٌ.خَاشِعَۃٌ: خَشَعَ سے اسم فاعل مؤنث کا صیغہ ہے اور خَشَعَ لَہٗ خُشَوْعًا کے معنے ہوتے ہیں ذَلَّ وَ تَطَاْمَنَ اس سے دب گیا.اس کے ماتحت ہو گیا یا اس کے سامنے اسے جھکنا پڑا.اور خَشَعَ بِبَصَـرِہٖ کے معنے ہوتے ہیں غَضَّہٗ اس نے اپنی آنکھیں نیچی رکھیں.اور خَشَعَ بَصَـرُہٗ کے معنے ہوتے ہیں اِنْکَسَـرَ اس کی نظر
Page 110
جھک گئی یعنی ذلّت اور رسوائی کی وجہ سے انسان نے آنکھ اونچی نہ کی.اور خَشَعَتِ الْاَصْوَاتُ لِلرَّحْمٰنِ کے معنے ہیں سَکَنَتْ وَذَلَّتْ وَخَضَعَتْ آوازیں دب گئیں اور خدا تعالیٰ کے سامنے ذلّت اور اقرارِ اتباع پر مجبور ہو گئیں (اقرب) پس وُجُوْهٌ يَّوْمَىِٕذٍ خَاشِعَةٌ کے معنے ہوئے اس دن کچھ سردارانِ قوم ہوں گے یا کچھ لوگ ہوں گے یا کچھ وجاہت والی ہستیاں ہوں گی جو بالکل ذلیل ہو جائیں گی اور ان کی آوازیں دب جائیں گی.نَاصِبَۃٌ.نَاصِبَۃٌ: نَصَبَ سے اسم فاعل مؤنث کا صیغہ ہے اور نَصَبَہُ الْھَمُّ کے معنے ہوتے ہیں اَتْعَبَہٗ غم نے اس کو تھکا دیا.اور نَصَبَ فُلَانٌ الشَّیْءَ کے معنے ہوتے ہیں وَضَعَہٗ وَضْعًا ثَابِتًا کَنَصْبِ الرُّمْـحِ وَالْبِنَاءِ وَالْـحَجَرِ یعنی کسی چیز کو مضبوطی سے گاڑ دیا جیسے نیزہ گاڑا جاتا ہے یا بنیاد کو مضبو ط بنایا جاتا ہے یا پتھر کو عمارت میں مضبوطی سے پیوست کر دیا جاتا ہے.وَ رَفَعَہٗ ضِدٌّ نیز یہ لفظ اضداد میں سے ہے اور اس کے معنے بلند کرنے کے بھی ہوتے ہیں اور نَصَبَ السَّیْـرَ کے معنے ہوتے ہیں رَفَعَہٗ اَوْ ھُوَ اَنْ یَّسِیْرَ طُوْلَ یَوْمِہٖ سَیْرًا لَیِّنًا اس نے سیر کو بلند کیا یعنی خوب تیزی سے سفر کیا یا آہستہ آہستہ سارا دن سفر کرتا رہا.گویا اس کے دونوں معنے ہیں.یہ بھی معنے ہیں کہ خوب گھوڑا دوڑایا اور یہ بھی معنے ہیں کہ آہستہ آہستہ دیر تک سفر کرتا چلا گیا.اور نَصَبَ لِفُلَانٍ کے معنے ہوتے ہیں عَادَاہُ اس سے دشمنی کی اور نَصَبَ لَہٗ الْـحَرْبَ کے معنے ہوتے ہیں وَضَعَھَا اس کے خلاف لڑائی کی اور نَصَبَ الْعَلَمَ کے معنے ہوتے ہیں رَفَعَہٗ وَاَقَامَہٗ مُسْتَقْبِلًا بِہٖ اس نے جھنڈے کو اپنے سامنے کھڑا کیا.اور نَصَبَ الشَّجَرَۃَ کے معنے ہوتے ہیں غَرَسَھَا فِی الْاَرْضِ اس نے زمین میں درخت گاڑا اور نَـصَـبَ السُّـلْــطَــانُ فُـلَانًـا کے معنے ہوتے ہیں وَلَّاہُ مَنْصَبًا اس کو بادشاہ نے کسی منصب پر مقرر کیا اور نَصَبَ الــشَّـــرَّ لِـــفُــلَانٍ کے معنے ہوتے ہیں اَظْــہَــرَہٗ لَـــہٗ اس کے خلاف منصوبہ بازی کی اور نَـــصَـــبْــتَ لَــہٗ رَأْیًـا کے معنے ہوتے ہیں اَشَـرْتَ عَــلَــیْــہِ بِـرَاْیٍ لَایَعْدِلُ عَــنْــہُ کہ تو نے ایسی رائے اس کو دی جس سے وہ ادھر ادھر نہ ہوسکا.(اقرب) عَامِلَۃٌ نَّاصِبَۃٌ کے آٹھ معنے پس عَامِلَۃٌ نَّاصِبَۃٌ کے معنے ہوئے عمل کرنے والی جماعت یا اعلان جنگ کرنے والی یا اپنی بنیادوں کو مضبوطی سے گاڑ دینے والی یا لمبے لمبے سفر کرنے والی یا اپنی دشمنیوں کا اظہار کرنے والی یا عہدوں پر مقرر کرنے والی یا اپنے جھنڈوں کو اونچا کرنے والی یا نیزوں کو گاڑنے والی جماعت (اقرب) غَاشِیَةٌ کے معنے چونکہ عام مشکلات اور مصائب کے بھی ہیں جن میں وہ لڑائیاں بھی شامل ہیں جو کفار سے
Page 111
ہوئیں.اس لحاظ سے عَامِلَۃٌ نَّاصِبَۃٌ کے یہ معنے ہوں گے کہ اب مخالفینِ اسلام تمہارے خلاف منصوبے کرنے والے ہیں اور ان بغضوں اور کینوں کو جن کو وہ اپنے دلوں میں چھپائے بیٹھے تھے ظاہر کرنے والے ہیں.تفسیر.یہ بتایا جا چکا ہے کہ سورۃ غاشیہ کا نزول رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ نبوت کے چوتھے سال کے قریب ہوا ہے اور یہی وہ سال ہے جس میں کفّار مکہ کی طرف سے منظّم رنگ میں ایذاء دہی کا سلسلہ شروع ہوا.ابتداء میں تو لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ نبوت کو سنتے تو کہتے.ہائے ہائے بےچارہ پاگل ہوگیا ہے (نعوذ باللہ من ذالک) اس طرح آپ کو مجنون اور پاگل کہہ کر وہ اپنے دل کا غصہ نکال لیتے تھے مگر جب کچھ لوگوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا خصوصاً نوجوان طبقہ میں سے ایک بااثر حصہ آپ کی بیعت میں شامل ہو گیا جن میں حضرت عثمانؓ حضرت طلحہؓ اور حضرت زبیرؓ خاص طور پر قابل ذکر ہیں تو کفار میں اسلام کے خلاف سخت جوش پیدا ہو گیا.ان کے دلوں میں اسلام کی مخالفت کا جوش پیدا کرنے والی دو چیزیں تھیں ایک غلاموں کا اسلام میں شامل ہونا.دوسرے رؤسا میں سے بعض نوجوانوں کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آنا.حضرت عثمانؓ، حضرت طلحہؓ اور حضرت زبیرؓ ایسے خاندانوں میں سے تھے جو مکہ کے رؤوسا میں شمار ہوتے تھے.جب یہ لوگ ایمان لے آئے تو وہ لوگ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم کو پاگل کہا کرتے تھے ان لوگوں نے طعنہ دینا شروع کر دیا کہ کیا یہ پاگل ہے یہ تو تمہارے گھروں میں سے نوجوانوں کو اپنی طرف کھینچ کر لے گیا ہے اور تم اسی خیال میں مست ہو کہ یہ پاگل ہے ہمارا کیا بگاڑ سکتا ہے.اسی طرح جب غلام مسلمان ہوئے اور کفار مکہ نے ان غلاموں کے منہ سے یہ باتیں سننی شروع کیں کہ بتوں کی پرستش بالکل بے ہودہ بات ہے ان میں رکھا ہی کیا ہے وہ تو کسی کو نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان.تو یہ باتیں ان کے لئے بالکل ناقابلِ برداشت ہو گئیں.کیونکہ اوّل تو ان کے بتوں کو برا بھلا کہا جاتا تھا اور پھر کہنے والے وہ تھے جو ان کے غلام تھے.یہ حالات تیسرے سال کے بعد پیدا ہونے لگ گئے تھے چنانچہ اسلام کی ترقی کو دیکھ کر انہوں نے علی الاعلان کہنا شروع کر دیا کہ اب مذاق ہو چکا.اب ہم ان باتوں کو برداشت نہیں کر سکتے.ہمارے ہاں بھی جب آپس میں مذاق ہو تو معمولی مذاق تو دوسرا شخص برداشت کرتاجاتا ہے لیکن جب بات بڑھنے لگے تو وہ کہہ دیتا ہے اب حد ہوگئی اب اس کے بعد اگر کوئی مذاق کیا تو میں تم سے لڑ پڑوں گا.اسی طرح تیسرے سال کے بعد کفّار مکہ نے کہنا شروع کر دیا کہ ہم تو ان باتوں کو مذاق سمجھتے تھے مگر اب تو حد ہوگئی اب یہ باتیں ہمارے لئے ناقابلِ برداشت ہو گئی ہیں چنانچہ انہوں نے اپنے بغضوں اور شرارتوں
Page 112
کا اعلان کردیا.(طبـری جلد دوم ذکر الـخبر عما کان من امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ ۲۲۳) پس ان کے اس اعلان کی ہی خبر خدا تعالیٰ نے وُجُوْهٌ يَّوْمَىِٕذٍ خَاشِعَةٌ عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ میں دی ہے کیونکہ نَاصِبَۃٌ کے ایک معنے افسر مقرر کرنے کے بھی ہوتے ہیں.اس لئے اس آیت میں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ وہ وقت آ رہا ہے جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں مکہ والے کمانڈر اور افسر مقرر کریں گے اور یہ لوگ پورا زور لگائیں گے کہ اسلام نہ پھیلے.چنانچہ پیشگوئی کے مطابق مخالفین نے مخالفت کے جھنڈے گاڑ دیئے اور مقابلہ کے لئے اتر آئے.پھر جن الفاظ میں مخالفین کی مخالفت کی خبر دی ہے وہ ایسے ہیں کہ ان سے مخالفت کی تفصیل اور اس کا انجام بھی معلوم ہو جاتا ہے.چنانچہ پہلے عَامِلَۃٌ کہا اور عَامِلَۃٌ میں انفرادی طور پر مکہ والوں کے مخالفت کرنے کا ذکر تھا مگر اس کے بعد نَاصِبَۃٌ کا لفظ استعمال کیا اور نَاصِبَۃٌ میں قومی طور پر مخالفت کرنے کا ذکر ہے اور اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اب مکہ والے صرف انفرادی طور پر نہیں بلکہ قومی طور پر اور اجتماعی رنگ میں بھی مخالفت کریں گے اور اپنے میں سے بعض کو افسر مقرر کریں گے تاکہ ایک تنظیم کے ماتحت وہ مسلمانوں سے لڑیں اور ان کو دِق کریں.پھر نَاصِبَۃٌ کے ایک معنے چونکہ تھکنے والی جماعت کے بھی ہیں.گویا آیت کے اس حصہ میں مخالفت کے انجام کی طرف اشارہ کر دیا کہ اہالیانِ مکہ مخالفت میں پوری محنت صرف کریں گے مگر اس کے نتیجہ میں ان کو کوئی خوشی نہیں پہنچے گی.محنت کریںگے لیکن نتیجہ تھکان ہی تھکان نکلے گا آرام و راحت میسر نہیں آئے گی.تَصْلٰى نَارًا حَامِيَةًۙ۰۰۵ وہ (سخت گرم اور) بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے.حلّ لُغات.حَامِیَۃٌ.حَامِیَۃٌ : حَـمِیَ سے ہے اور حَـمِیَتِ النَّارُ کے معنے ہوتے ہیں اِشْتَدَّ حَرُّھَا آگ نہایت تیزی کے ساتھ بھڑک اٹھی (اقرب) پس حَامِیَۃٌ کے معنے ہوں گے شدت سے بڑھکنے والی اور تَصْلٰى نَارًا حَامِيَةً کے معنے ہوں گے کہ مخالف جماعتیں بھڑکتی آگ میں داخل ہوں گی.ساری آگیں ایک قسم کی نہیں ہوتیں بعض آگیں زیادہ گرم ہوتی ہیں اور بعض کم گرم.یہاں تک کہ بعض آگیں ایسی ہوتی ہیں کہ لوگ ننگے پاؤں صرف پاؤں کو کیچڑ لگا کر ان کے اوپر سے گذر جاتے ہیں اور انہیں کوئلوں کی گرمی محسوس نہیں ہوتی.مگر فرماتا ہے کہ وہ آگ جس میںمخالفین داخل ہوں گے وہ نَارًا حَامِيَةً ہو گی یعنی ایسی آگ جو اپنی تیزی اور اپنی گرمی میں
Page 113
انتہا پر پہنچ چکی ہو گی.تفسیر.تَصْلٰى نَارًا حَامِيَةً میں مخالفین کی ناکامی کی پیشگوئی فرماتا ہے یہ مخالفت چاہے انفرادی ہو یا قومی مخالفین کی تباہی کا موجب ہو گی اور بجائے اس کے کہ مخالف لوگ امن و آرام پائیں یا انہیں عزّت اور کامیابی حاصل ہو یہ اس آگ میں داخل ہوں گے جو سخت گرم ہو گی اور بھڑکنے میں تیز ہو گی یعنی مسلمان ترقی کر جائیں گے اور مخالفین اپنے منصوبوں میں ناکام و نامراد رہیں گے اور آگ میں جلیں گے.تُسْقٰى مِنْ عَيْنٍ اٰنِيَةٍؕ۰۰۶ انہیں ابلتے ہوئے چشمہ سے (پانی) پلایا جائے گا.حلّ لُغات.عَیْنٌ.عَیْنٌ کے عربی زبان میں بہت سے معنے ہیں ان معنوں میں سے ایک چشمہ کے ہیں اور دوسرے معنے بادل کے ہیں (اقرب) اس آیت میں چونکہ تُسْقٰى کا لفظ استعمال ہوا ہے اس لئے عَیْنٌ سے مراد چشمہ یا بادل ہی ہو سکتا ہے.اٰنِیَۃٌ.اٰنِیَۃٌ: اَنَی ( یَاْنِی اَنْیًا وَ اِنًی وَاَنَاءً )سے ہے اور اَنَی کے معنے ہوتے ہیں دَنٰی وَقَرُبَ وَحَضَـرَ.وہ قریب ہو گیا اور سامنے آ گیا.جب پانی کے متعلق یہ لفظ بولا جاتا ہے تو اس کے معنے ہوتے ہیں اِنْتَـھٰی حَرُّہٗ کہ پانی سخت گرم ہو گیا (اقرب) جیسے آگ کے متعلق کہتے ہیں حَـمِیَتِ النَّارُ یعنی آگ سخت بھڑک اٹھی اسی طرح پانی کے لئے جب یہ لفظ استعمال کیا جائے تو اس کے معنے ہوتے ہیں وہ تیز گرم ہو گیا.پس تُسْقٰی مِنْ عَیْنٍ اٰنِیَۃٍ کے یہ معنے ہوئے کہ انہیں ایسے چشمے سے پانی پلایا جائے گا جو نہایت تیز گرم ہو گا یا ایسے بادلوں سے ان پر پانی برسے گا جو نہایت شدید گرم ہوں گے اور ان کو جھلس کر رکھ دیں گے.تفسیر.انسان پانی پیتا ہے تو اس کی غرض یہ ہوتی ہے کہ پیاس بجھے اور پیاس ہمیشہ ٹھنڈا پانی بجھاتا ہے.لیکن یہاں یہ ذکر ہے کہ ان کو سخت کھولتا ہوا گرم پانی پلایا جائے گا.گرم پانی انسان دو ہی حالتوں میں پیتا ہے یا تو اس وقت جب بیمار ہو اور علاج کے لئے اسے گرم پانی پینا پڑے اور یا پھر اس وقت جب ٹھنڈا پانی اسے میسر نہ آئے اور مجبوراً گرم پانی پینا پڑے.(گو اس زمانہ میں لوگوں میں چائے کا طریق مروج ہو گیا ہے جو گرم بھی ہوتی ہے اور پیاس بجھانے کے لئے بھی استعمال کی جاتی ہے مگر وہ درحقیقت ایک غذ اہے پانی کا قائم مقام نہیں) پس
Page 114
گرم پانی پینے کا ذکر فرما کر اس طرف اشارہ کیا ہے کہ وہ ہر آرام سے محروم ہو جائیںگے یا یہ کہ ان کی روحانی امراض کو دور کرنے کے لئے انہیں ابتلاؤں میں ڈالا جائے گا اور ایسے گرم چشمہ سے ان کو پانی پلایا جائے گا جس کی گرمی انتہا درجہ تک پہنچی ہوئی ہو گی.یعنی پانی پینے کی جو اصل غرض ہوتی ہے کہ انسانی جسم پر تروتازگی آئے وہ ان کو حاصل نہیں ہو گی.دنیا میں دو قسم کی چیزیں ہیں.ایک تو ایسی ہیں جو نضارت اور تروتازگی پیدا کرتی ہیں اور ایک ایسی ہیں جو موٹاپا پیدا کرتی ہیں.ان میں سے ایک مقصد غذا سے اور دوسرا مقصد پانی سے حاصل ہو جاتا ہے.پانی پینے سے تروتازگی حاصل ہوتی ہے اور غذا کھانے سے بھوک دور ہوتی اور جسم فربہ ہوتا ہے.کفار کے متعلق بتایا کہ ان کو یہ دونوںباتیں حاصل نہیں ہوں گی.نہ ان کے اندر تازگی پائی جائے گی اور نہ ان کے جسم پر گوشت چڑھے گا یعنی ان کے دل بھی مرجھا جائیں گے اور ان کے جسم بھی مرجھا جائیں گے.کھولتے ہوئے چشمہ سے پانی پینے سے مراد کھولتا ہوا چشمہ آخرت میں تو ہو گا ہی دنیا میں کھولتے ہوئے چشمہ سے مراد وہ چیز ہوتی ہے جس سے دل کو آگ لگ جائے.مطلب یہ ہے کہ کفار کو ایسے مصائب پہنچیں گے اور ایسے حالات میں سے وہ گذریں گے کہ ان کے دل جل جائیں گے.یہ عَیْنٍ اٰنِیَۃٍ ہی تھا کہ ان کی اولادیں مسلمان ہو گئیں اور جس مذہب کو مٹانے کے لئے وہ کھڑے ہوئے تھے اسی مذہب میں ان کے بیٹے شامل ہوگئے.جب وہ اپنی اولادوں کو اسلام میں شامل ہوتے دیکھتے ہوں گے تو کس طرح ان کے دل جلتے ہوں گے کہ ہم کیا چاہتے تھے اور کیا ہو گیا.ہمارے ہاں بھی محاورہ کے طور پر کہا جاتا ہے کہ میں تو غم کے گھونٹ پی رہا ہوں.گویا غم کی چیزوں کو بھی پینے سے مشابہت دی جاتی ہے.عربی زبان میں بھی غم کے گھونٹ پینا محاورہ کے طور پر استعمال ہوتا ہے.پس فرماتا ہے ان کو گرم اور تیز گھونٹ پلائے جائیں گے یعنی ایک طرف ان کی اولادیں اور دوسری طرف غلام مسلمان ہونے لگ جائیں گے جس کا ان کو شدید صدمہ پہنچے گا.قرآن کریم میں اس حقیقت کو دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے اَوَلَمْ یَرَوْا اَنَّا نَاْتِی الْاَرْضَ نَنْقُصُھَا مِنْ اَطْرَافِھَا (الرعد:۴۲) یعنی یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم پر غالب آ جائیں گے.آپؐکے دین کو مٹا دیں گے اور مسلمانوں کو شکست دے دیں گے کیا ان اندھوں کو یہ بات نظر نہیں آتی کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے چھوٹا کرتے چلے آ رہے ہیں ادھر غلام اسلام میں داخل ہو رہے ہیں اور ادھر نوجوان اسلام کو قبول کر رہے ہیں جب غلام اور نوجوان دونوں اسلام میں داخل ہو گئے تو پیچھے سوائے بڈھوں کے کون رہ جائے گا.یہ بڈھے چند سالوں میں مر کر فنا ہو جائیں گے اور ان کی نسلیں اسلام میں شامل ہو جائیں گی.دنیا میں طاقت کے یہی دو ذرائع ہوتے ہیں
Page 115
ایک غلام جو ہاتھ ہوتے ہیں اور دوسری آئندہ نسلیں جو جڑ ہوتی ہیں.جب ان کے پاس نہ ہاتھ رہے گا نہ جڑ تو درمیان کا ٹنڈ کیا کرے گا.غرض اس آیت میں اللہ تعالیٰ اسلام کی ترقی کی خبر دیتے ہوئے فرماتا ہے ان کفار کو عَیْنٍ اٰنِیَۃٍ یعنی گرم چشمہ سے گھونٹ پینے پڑیں گے اور یہ ایسی خبریں سنیں گے جن سے ان کے سینے جلنے لگ جائیںگے ہم دیکھتے ہیں کہ واقعہ میں اگر کوئی شخص کسی مذہب کو سچے دل سے قبول کرتا ہے تو اس کی اولاد کا اس سے پھرنا اس کے لئے انتہائی طور پر دکھ کا موجب ہوتا ہے عقلی طور پر اگر اولاد مذہب سے منحرف ہو جاتی ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، مذہب کے معاملہ میں جبر سے کام نہیں لیا جا سکتا.حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا اگر ان کا مخالف ہو سکتا ہے تو دوسرے لوگوں کی اولادیں بھی اپنے باپ دادا کے مذہب سے انحراف اختیار کر سکتی ہیں مگر جہاں کوئی اور قائم مقام نہ ہو اور وہ اولاد جس سے انسان کی امیدیں وابستہ ہوں اپنے باپ دادا کے مذہب کو ترک کر دے تو یہ ایک ایسا تلخ گھونٹ ہے جس کا پینا انسانی طاقت برداشت سے بالکل باہر ہوتا ہے.کفار کے تلخ گھونٹ پینے کے بعض واقعات حدیبیہ کے مقام پر جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفّار سے صلح کی شرائط طے کرنے لگے تو اس وقت کفار کی طر ف سے سہیل ابن عمرو نمائندہ تھے.اسی اثناء میں کہ ابھی شرائط صلح طے ہی ہو رہی تھیں کہ اس کا بیٹا ابوجندل ایسی حالت میں وہاں آ پہنچا کہ اس کے پاؤں بیڑیاں پڑی ہوئیں تھیں (سیرۃ ابن ہشام زیر عنوان ’’علیٌّ یکتب شروط الصلح‘‘) اور اس نے آتے ہی کہا یا رسول اللہ میں مسلمان ہوں اور آپ پر ایمان لا چکا ہوں.گھر میں تو اس کا باپ اسے مارپیٹ کر غصہ نکال لیتا ہو گا مگر اس وقت جب اسی کا لڑکا جسے اس نے زنجیروں میں جکڑ کر گھر میں قید کیا ہوا تھا لڑکھڑاتا اور گرتا پڑتا وہاں پہنچا ہو گا اور اس نے کہا ہو گا کہ یا رسول اللہ میں آپ پر ایمان لا چکا ہوں تو اس وقت اس کا کیا حال ہوا ہو گا.میں سمجھتا ہوں اس کے لئے اٹھنا مشکل ہو گیا ہو گا اور وہ کہتا ہو گا کاش اس وقت زمین پھٹ جائے تو میں اس میںسما جاؤں.ایسے نازک وقت میں اس کے اپنے بیٹے کا کفر سے اسی طرح برأت کا اظہار کرنا اس کے لئے کتنا تلخ گھونٹ تھا جو اسے پینا پڑا.اسی طرح ابوجہل کا واقعہ میںنے کئی دفعہ بیان کیا ہے.وہ جنگ بدر میں دو نوجوان لڑکوں کے ہاتھ سے مارا گیا اور آخری وقت اس نے یہی کہا کہ مجھے اور تو کوئی صدمہ نہیں مگر افسوس ہے تو یہ کہ میں دو انصاری لڑکوں کے ہاتھ سے مارا گیا ہوں.(صحیح بخاری کتاب المغازی باب قَتْلِ اَبِیْ جَھْلٍ)
Page 116
غرض اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ کفار ایسے حالات میں سے گذریں گے کہ ان کو بڑے بڑے تلخ گھونٹ پینے پڑیں گے.حضرت مسیح موعودؑ کے مخالفین کے لئے تُسْقٰى مِنْ عَيْنٍ اٰنِيَةٍ کا نظارہ میں نے شروع میں بتایا ہے کہ یہ سورۃ دونوں زمانوں کے ساتھ تعلق رکھتی ہے.اسلام کے ابتدائی زمانہ کے ساتھ بھی اور موجودہ زمانہ کے ساتھ بھی.تُسْقٰى مِنْ عَيْنٍ اٰنِيَةٍ میں کفار کے متعلق اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو خبر دی گئی تھی وہ اس زمانہ میں بھی بڑی صفائی کے ساتھ پوری ہوئی ہے.مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے شدید مخالف تھے اور ان کی ساری عمر آپ کی مخالفت کرتے گذر گئی.انہوں نے ایک دفعہ بڑی تعلّی کے ساتھ کہا تھا کہ میں نے ہی مرزا صاحب کو اونچا کیا تھا اور اب میں ہی ان کو نیچے گراؤں گا.(اشاعۃ السنہ جلد ۱۳ صفحہ ۴) مگر اس کے بعد انہوںنے حضرت مرزا صاحب کو کیا گرانا تھا خود ہی ذلیل ہوتے گئے یہاں تک کہ ان کے دو بیٹے بھاگ کر قادیان میں میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارا باپ اتنا بے غیرت ہے کہ وہ ہمیں کہتا ہے کہ ہم کسی یتیم خانہ میں داخل ہو جائیں.وہ ہمیں ہر وقت مارتا پیٹتا ہے اور ہم سے ذلیل کام لیتا ہے ہم اب اس کے پاس نہیں رہنا چاہتے.میں نے ان دونوں کا وظیفہ لگا دیا اور انہیں قادیان میںتعلیم دلائی.مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے کہلا بھیجا کہ اس میں میری بڑی ذلّت ہے ان کو قادیان سے نکال دیں.مگر میں نے کہا یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ میرے پا س مدد کے لئے آئیں اور میں ان کو نکال دوں.اس کے بعد وہ دونوں احمدی ہو گئے.اور آخر مولوی صاحب زور دے کر ان کو واپس لے گئے مگر پھر بھی ان سے ایسا سلوک کیا کہ ان میں سے ایک تو مر گیا ہے مگر دوسرا عیسائی ہو گیا اور اب تک زندہ ہے اور ریاست میسور میں کاروبار کرتا ہے وہ کہتا ہے میں دل سے تو احمدی ہوں مگر روزی کے لئے مذہب تبدیل کیا ہوا ہے.یہ کتنا تلخ گھونٹ تھا جو مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی کو پینا پڑا.وہ شخص جس نے کہا تھا کہ میں نے ہی مرزا صاحب کو اونچا کیا تھا اور اب میں ہی ان کو نیچے گراؤں گا اس کے اپنے لڑکے ہمارے پاس مدد کے لئے آئے.اور انہوں نے کہا کہ ہمارا باپ ہم کو مارتا ہے پیٹتا ہے اور کھانے کے لئے روٹی تک نہیں دیتا.کہتا ہے کہ یتیم خانے میں داخل ہو جاؤ میرے پاس تمہارے لئے کچھ نہیں.چنانچہ ہم نے ان کی مدد کی اور اپنے مدرسہ میں رکھ کر تعلیم دلائی پس یہ واقعہ مولوی محمد حسین صاحب کے لئے کتنا تلخ گھونٹ تھا جو ان کو پینا پڑا.اسی طرح ایک اور مشہور مخالف جو ہمارے شدید مخالفوں کا سردار ہے اس کے بیٹے پر ایک مقدمہ دائرہوا.
Page 117
جس مجسٹریٹ کے پاس وہ مقدمہ گیا اتفاق سے وہ احمدی تھا.وہ احمدی مجسٹریٹ مجھ سے ملنے کے لئے آئے تو انہوں نے ذکر کیا کہ فلاں مخالف کے لڑکے کا مقدمہ میرے پاس ہے اور وہ اس کے متعلق بڑی سفارشیں بھجوا رہا ہے کہ اسے چھوڑ دیا جائے.میں نے انہیں کہا کہ اگر آپ اسے جائز طور پر چھوڑ سکتے ہیں تو ضرور چھوڑ دیں تا کہ اس کے باپ کو شرم محسوس ہو کہ میں تو جماعت احمدیہ کی مخالفت کرتا رہا مگر احمدی مجسٹریٹ نے میرے بچے کو رہا کر دیا.یہ ایسا احسان ہو گا جو ساری عمر اس کی آنکھیں نیچی رکھے گا.اس لئے جائز طور پر اور قانون کی مناسب تشریح سے اگر آپ اس کو چھوڑ سکتے ہوں تو ضرور چھوڑ دیں.اسی طرح میں جب حج کے لئے گیا تو ہمارے ایک رشتہ دار جو ہمارے نانا جان مرحوم کی ہمیشرہ کے بیٹے تھے اور اس لحاظ سے ہمارے ماموں تھے اور بھوپال کے رہنے والے تھے انہوں نے اور ان کے ساتھ ہی ایک اور شخص نے جو بھوپال کے رہنے والے تھے اور نواب جمال الدین خاں صاحب کے نواسے تھے اور جن کا نام خالد تھا ہمارے خلاف سخت شورش شروع کر دی اور لوگوں کو یہ کہہ کر بھڑکانا شروع کر دیا کہ یہ لوگ کفر پھیلاتے ہیں اور ساتھ ہی مولوی ابراہیم صاحب سیالکوٹی کو (جو اس سال حج کو گئے تھے) مباحثہ کے لئے آمادہ کرنا شروع کیا اور ان کی غرض یہ تھی کہ اس طرح ان کا اعلان کثرت سے ہو گا اور مباحثہ ہوا تو لوگ جوش میں آ کر انہیں قتل کر دیں گے گورنمنٹ کو انہوں نے یا ان کے ساتھیوں نے توجہ دلائی کہ ان کے خلاف فوری کارروائی کرے اور اس فتنہ کو بڑھنے سے روکے لیکن ہمیں ان کی اس اشتعال انگیزی کا کوئی علم نہ تھا.میں ایک دن ایک عرب عالم مولانا عبدالستار کبتی کو جو شریف مکہ کے بیٹوں کے استا د تھے تبلیغ کرنے کے لئے گیا.وہ بہت ہی شریف الطبع آدمی تھے عقیدۃً وہابی تھے مگر اپنے آپ کو وہابی ظاہر نہیں کرتے تھے بلکہ حنبلی ظاہر کرتے تھے انہوںنے باتوں باتوں میں اپنے متعلق خود ہی بتایا کہ میں ہوں تو اہل حدیث لیکن یہاں اہل حدیثوں کو چونکہ لوگ سخت نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اس لئے میں اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتا.تعلیم کا کام بھی میں مفت اس لئے کرتا ہوں تا کہ شریف کے خاندان کی امداد حاصل رہے.اس پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے کوئی شخص میرے خلاف شرارت کرنے کی جرأت نہیں کر سکتا.آدمی بڑے شریف تھے میں ان کو کافی دیر تک تبلیغ کرتا رہا.جاتی دفعہ حضرت خلیفہ اوّل رضی اللہ عنہ نے مجھے ایک کتاب کے متعلق فرمایا تھا کہ اس کا عرب ممالک سے پتہ لگانا.انہیں بھی کتابوں کا شوق تھا میں نے ان سے اس کتاب کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ کتا ب میرے پاس تو نہیں لیکن حلب کے کتب خانہ میں موجود
Page 118
ہے.جب میں تبلیغ سے فارغ ہوا تو وہ کہنے لگے آپ نے مجھے تو تبلیغ کر لی ہے اور آپ کی باتیں بھی معقول ہیں لیکن میرے سوا اور کسی کو آپ تبلیغ نہ کریں ورنہ آپ کی جان کی خیر نہیں.لوگ بہت جوش میں ہیں اگر آپ نے تبلیغ کی تو خطرہ ہے کہ آپ پر کوئی شخص حملہ نہ کر بیٹھے یا حکومت ہی آپ کو قید نہ کر دے.میں نے اس پر تعجب کا اظہار کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کو معلوم نہیں آپ کے خلاف بعض لوگوں نے یہاں اشتہار شائع کیا ہے اور لوگ سخت جوش میں بھرے ہوئے ہیں.میں نے کہا کس نے وہ اشتہار شائع کروایا ہے؟ تو انہوں نے کہا ایک تو اس اشتہار کے محرک فلاں مولوی صاحب ہیں.میں نے کہا وہ تو میرے ماموں ہیں.اور کون صاحب ہیں؟ انہوں نے کہا دوسرے بھوپال کے ایک رئیس ہیں جن کا نام خالد ہے.ان دونوں نے آپ کے خلاف اشتہار دیا ہے یا دلوایا ہے اور لکھا ہے کہ اگر انہیں اپنے دعاوی کی صداقت پر یقین ہے تو مولوی ابراہیم صاحب سیالکوٹی سے مباحثہ کر لیں.مولوی ابراہیم صاحب سیالکوٹی بھی ان دنوں وہیں تھے اور ہمارے ماموں کا یہ خیال تھا کہ مکہ میں چونکہ باقاعدہ حکومت کوئی نہیں اس لئے اگر مباحثہ ہوا تو لوگ انہیں مار ڈالیں گے اور اس طر ح ایک کانٹا نکل جائے گا.مولانا عبدالستارصاحب کبتی فرمانے لگے میں نے مولوی ابراہیم صاحب سیالکوٹی سے کہا ہے کہ کہیں جوش میں مباحثہ نہ کر بیٹھنا کیونکہ یہاں احمدیوں کی اتنی مخالفت نہیں جتنی وہابیوں کی ہے اس لئے لوگوںکو کیوں خواہ مخواہ اپنے خلاف اشتعال دلاتے ہو.احمدیوں کے خلاف کسی کو اشتعال آیا یا نہ آیا تمہارے خلا ف تو لوگ ضرور بھڑک اٹھیں گے اس لئے وہ تو شاید اس ڈر سے مقابلہ نہ کریں کہ کہیں شورش زیادہ نہ ہو جائے مگر آپ کسی اور کو اب تبلیغ نہ کریں ایسا نہ ہو کہ آپ کو کوئی نقصان پہنچ جائے.میں نے کہا آپ کس کی طرف سے زیادہ خطرہ سمجھتے ہیں؟ انہوں نے ایک عالم کا نام لیا کہ اسے تو بالکل تبلیغ نہ کرنا.میں نے کہا میں تو اسے ایک گھنٹہ تبلیغ کر کے آ رہا ہوں.وہ حیران ہو کر بولے پھر کیا ہوا؟ میں نے کہا کہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد وہ غصہ اور جوش کی حالت میں کہہ دیتے تھے کہ نہ ہوئی تلوار ہمارے قبضہ میں ورنہ تمہارا سر اڑا دیتا.غرض وہ ہمارے ماموں اور بھوپال کے رئیس ہمارے خلاف لوگوں کو خوب بھڑکاتے رہے لیکن ادھر حج ختم ہوا اور اُدھر مکہ میں ہیضہ پھوٹ پڑا جو اتنا شدید تھا کہ لوگ گلیوں میں مردوں کو پھینک دیتے تھے دفن کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا تھا یہ دیکھ کر نانا جان گھبرا گئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں جلدی واپس چلنا چاہیے.چنانچہ ہم نے واپسی کی تیاری شروع کر دی اور آخری ملاقات کے لئے نانا جان صاحب مرحوم اپنی بہن اور بھانجا سے ملنے کے لئے ان کے مکان پر گئے میں بھی ساتھ تھا.جب ہم وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک جنازہ
Page 119
پڑا ہے لوگ جمع ہیں اور تدفین کی تیاری ہو رہی ہے.نانا جان نے ان لوگوں سے پوچھا کہ یہ کس کا جنازہ ہے؟ لوگوں نے ہمارے ماموں کا نام لیا کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے.منٰی سے واپس آئے تھے کہ ہیضہ کا حملہ ہو گیا اور تھوڑی دیر میں ہی فوت ہو گئے.ایک کا تو یہ حال ہوا.جب ہم جدّہ پہنچے تو جدّہ کے انگریزی قنصل خانہ میں بھی ہمارے ننھیال کے ایک رشتہ دار ہیڈ کلرک تھے.بھوپال کے جس رشتہ دار کا میں نے ذکرکیا ہے وہ تو نانا جان مرحوم کے رشتہ داروںمیں سے تھے اور یہ نانی اماں صاحبہ مرحومہ کے رشتہ داروں میں سے تھے.یہ ایک عجیب بات ہے کہ ہمارے جتنے رشتہ دار نانا جان مرحوم کی طرف سے تھے وہ بالعموم مخالف تھے اور جتنے نانی اماں کی طرف سے تھے وہ بالعموم محبت کرنے والے تھے (مگر اب حالات وہ نہیں رہے) یہ غالبًا ان کی خالہ کے لڑکے تھے اور ہم سے بہت محبت کرتے تھے.جہاز چونکہ کم تھے اور لوگ جلدی واپس ہونا چاہتے تھے اس لئے ٹکٹ ملنے میں سخت دشواری تھی.ہم نے ان سے کہا کہ ٹکٹوں کا جلدی انتظام کر دیں تاکہ ہم پہلے جہاز میں واپس ہو سکیں.انہوں نے جہاز ران کمپنی کے دفتر میں مجھے بٹھا دیا اور میں اس کی کھڑکی کے قریب بیٹھ گیا.یہ کھڑکی بہت اونچی تھی اور وہاں ہاتھ بمشکل اونچا کر کے پہنچ سکتا تھا.اتنے میں ایک نوجوان جو دبلے پتلے سفید رنگ کے تھے اس کھڑکی کے نیچے آئے انہوں نے مجھے بیٹھے ہوئے دیکھ کر خیال کیا کہ شاید میں کمپنی کا ملازم ہوں چنانچہ مجھ سے پوچھنے لگے کہ آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ میں نے کہا آپ کا اس سے کیا مطلب؟ انہوں نے کہا میرا مقصد یہ ہے کہ کیا آپ کمپنی میں کام کرتے ہیں؟ میں نے کہا میں تو کمپنی میں کام نہیں کرتا.کہنے لگے تو کیا کمپنی سے کوئی اور تعلق ہے؟ میں نے کہا میرا کمپنی سے کسی قسم کا تعلق نہیں.وہ کہنے لگے پھر آپ کمپنی کے دفتر میں بیٹھے کیوں ہیں؟ میں نے کہا میرے ایک عزیز مجھے یہاں بٹھا گئے ہیں اور وہ خود ٹکٹوں کی خرید کا انتظام کر رہے ہیں.اس پر انہوں نے کہا کہ ہمارا قافلہ تیس بتیس عورتوں اور مردوں پر مشتمل ہے اور اس وقت سخت مصیبت کا سامنا ہے مگر ہمیں سب سے زیادہ فکر عورتوں کا ہے ہیضہ کی وجہ سے عورتیں تو پاگل ہو رہی ہیں اگر آپ دس بارہ ٹکٹ خرید دیں تو ہم عورتوں کو یہاں سے نکال دیں مردوں کے ساتھ جو گذرے گی گذر جائے گی.میں نے کہا عورتیں اکیلی کس طرح جائیں گی؟ اس پر وہ کہنے لگے اگر آپ دو چار اور ٹکٹ لے دیں تو کچھ مرد بھی ان کے ساتھ جا سکیں گے اور آپ کی یہ بڑی مہربانی ہو گی.میں نے کہا ٹکٹوں کی خرید کے ساتھ میرا کوئی تعلق تو نہیں مگر میں کوشش کرتا ہوں.وہ فوراً پیچھے پلٹ کر گئے اور واپس آ کر ایک تھیلی روپوں کی انہوں نے مجھے پکڑا دی.جب میرے وہ عزیز
Page 121
لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ اِلَّا مِنْ ضَرِيْعٍۙ۰۰۷ انہیں سوکھے شبرق گھاس کے سوا اور کوئی کھانا نہیں ملے گا لَّا يُسْمِنُ وَ لَا يُغْنِيْ مِنْ جُوْعٍؕ۰۰۸ وہ نہ تو انہیں موٹا کرے گا اور نہ بھوک (کی تکلیف) سے بچائے گا.حلّ لُغات.اَلضَّـرِیْعُ.اَلضَّـرِیْعُ: اَلضَّـرِیْعُ نَبَاتٌ رَطْبُہٗ یُسَمّٰی شِبْرَقًا وَیَابِسُہٗ ضَـرِیْعًا لَاتَقْرُبُہٗ دَابَّۃٌ لِـخُبْثِہٖ.یعنی ضریع گھاس کی ایک قسم ہوتی ہے جب تک وہ گھاس تازہ رہے اسے شبرق کہتے ہیں اور جب سوکھ جائے تو ضریع کہتے ہیں ضریع ایسی گندی چیز ہوتی ہے کہ جانور بھی اس کو نہیں کھاتے.اسی طرح ضریع ایسی گھاس کو بھی کہتے ہیں جو سمندر کے کنارے اُگ آتا ہے مگر چونکہ نہایت گندہ اور بد بو دار ہوتا ہے لوگ اسے کاٹ کر پانی میں بہا دیتے ہیں.اسی طرح ہر درخت کی سوکھی ٹہنی یا سوکھے پتوں کو بھی ضریع کہتے ہیں.اسی طرح سڑے ہوئے پانی میں ایک بوٹی ہوتی ہے اس کو بھی ضریع کہتے ہیں.(اقرب) لغت والوں نے اس کی جو تشریح کی ہے اس سے میں سمجھتا ہوں کہ غالباً اس سے کائی مراد ہے کیونکہ وہ لکھتے ہیں نَبَاتٌ فِی الْمَآءِ الْاَجِنِ لَہٗ عُرُوْقٌ لَاتَصِلُ اِلَی الْاَرْضِ سڑے ہوئے پانی میں ایک بوٹی ہوتی ہے جس کی جڑیں زمین میں نہیں جاتیں پانی میں ہی رہتی ہیں یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جن میں کوئی غذائیت نہیں ہوتی اور جنہیں انسان چھوڑ جانور بھی نہیں کھاتے.پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَیْسَ لَھُمْ طَعَامٌ اِلَّا مِنْ ضَرِیْعٍ کہ ان کو سوائے ضریع کے اور کوئی کھانا نہیں ملے گا.تفسیر.علامہ زمخشری لکھتے ہیں اس آیت کے معنے یہ ہیں کہ ان کوکوئی کھانا نہیں ملے گا کیونکہ ضریع کوئی کھانا نہیں ہے ( الکشاف سورۃ غاشیہ زیر آیت ’’ لَیْسَ لَھُمْ طَعَامٌ اِلَّا مِنْ ضَرِیْعٍ ‘‘) لیکن بحر محیط والوں نے اس پر بڑی عمدہ جرح کی ہے وہ لکھتے ہیں کہ یہ درست نہیں.قرآن کریم کہتا ہے کہ لَیْسَ لَھُمْ طَعَامٌ اِلَّا مِنْ ضَرِیْعٍ ضریع کھانا ہو یا نہ ہو مگر جس کو کھانے کے لئے کچھ نہیں ملتا وہ اپنا پیٹ بھرنے کے لئے کچھ نہ کچھ کھا ہی لیتا ہے خواہ عام حالات میں وہ چیز کھانے کے ناقابل ہی کیوں نہ ہو.جب اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد صاف طور پر فرما دیا ہے کہ لَا یُسْمِنُ وَلَا یُغْنِیْ مِنْ جُوْعٍ تو یہ کیوں کہتے ہو کہ ان کو کھانا نہیں ملے گا.قرآن کریم کا اسلوبِ بیان اور اس
Page 122
کے الفاظ واضح کر رہے ہیں کہ ان کو کھانے کے لئے ضریع دیا جائے گا یعنی وہ ایسے ذلیل ہو جائیں گے کہ ایسی چیزیں کھانے پر مجبور ہوں گے جن کو جانور بھی نہیں کھاتے.مطلب یہ ہے کہ ان کو ایسی ایسی ذلّتیں اور رسوائیاں پہنچیں گی کہ جن کو ادنیٰ ادنیٰ انسان بھی برداشت نہیں کر سکتے.فتح مکہ کے بعد کئی آدمی جنگلوں میں بھاگ کر چلے گئے تھے اور وہیں مر گئے.پھر بعض لوگ تھے جو بڑی بڑی تلخیاں برداشت کرنے کے بعد مکہ میں واپس آئے اور انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی جس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف فرما دیا.(اسد الغابۃ جلد ۳ زیر حالات عکرمہ بن ابی جہل) جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا تو وہ لوگ جو کہا کرتے تھے کہ ہم مسلمانوں کو تباہ کر دیں گے.ان کو کچل کر رکھ دیں گے.ان کو مٹا دیں گے جب اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوں گے کہ مسلمان غلام ان کے حاکم اور سردار بنے ہوئے ہیں تو خواہ وہ اعلیٰ درجہ کا کھانا ہی کیوں نہ کھاتے ہوں مگر وہ انہیں ضریع سے کم محسوس نہیں ہوتا ہوگا اور وہ کھان ان کے انگ نہیں لگتا ہو گا.یہ ضروری نہیں کہ ضریع سے مراد یہاں حقیقتاً شبرق گھاس ہی ہو بلکہ آگے جو تشریح کی گئی ہے کہ لَا یُسْمِنُ وَلَا یُغْنِیْ مِنْ جُوْعٍ وہ کھانا نہ ان کو موٹا کرے گا اور نہ ان کی بھوک کو دور کرے گا یہ ان کی بدحواسی کی حالت کو ظاہر کر رہا ہے.پس بالکل قرین قیاس ہے کہ ضریع کا ذکر استعارۃً ہے.لَیْسَ لَھُمْ طَعَامٌ اِلَّا مِنْ ضَرِیْعٍ اور تُسْقٰى مِنْ عَيْنٍ اٰنِيَةٍ میں اسلام کی ترقی اورکفار کے تنزل کی پیشگوئی وہ روزانہ دیکھتے تھے کہ مسلمان ترقی کر رہے ہیں اور ہم شکست کھاتے جا رہے ہیں.پھر ہر لڑائی میں انہیں خبریں پہنچتی تھیں کہ آج فلاں رئیس مر گیا ہے.آج فلاں سردار مر گیا ہے یا آج فلاں قوم مسلمانوں سے مل گئی ہے اور فلاں قوم نے بھی اسلام قبول کرلیا ہے.یہ خبریں ان کے لئے اس قدر پریشان کن.اس قدر تکلیف دہ اور اس قد ر غم و الم میں مبتلا کرنے والی تھیں کہ واقعہ میں اچھی سے اچھی غذائیں کھا کر بھی وہ ان کے انگ نہیں لگ سکتی تھیں.الغرض لَیْسَ لَھُمْ طَعَامٌ اِلَّا مِنْ ضَرِیْعٍ لَّایُسْمِنُ وَلَا یُغْنِیْ مِنْ جُوْعٍ اور اسی طرح تُسْقٰى مِنْ عَيْنٍ اٰنِيَةٍ میں اسلام کی ترقیات کے متعلق زبردست پیشگوئی کی گئی ہے.عیسائی مصنّف بھی تسلیم کرتے ہیں کہ یہ سورۃ ابتدائی ایام کی ہے جب کہ ابھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ نبوت پرصرف تین چار سال گذرے تھے یہ کتنا بڑا نشان ہے کہ ان ابتدائی ایام میں ہی اللہ تعالیٰ نے بتادیا کہ ان کفار سے جنگ ہو گی.قحط کی صورت میں ان پر عذاب نازل ہو گا.وہ انفرادی کوششیں بھی اسلام کو مٹانے
Page 123
کے لئے کریں گے اور اجتماعی کوششیں بھی اسلام کے خلاف صرف کریں گے چنانچہ عَامِلَۃٌ نَّاصِبَۃٌ میں اسلام کی طرف سے مخالفین اسلام کو اسی رنگ میں چیلنج دیا گیا تھا جس رنگ میں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے دشمنوں کو دیا کہ يٰقَوْمِ اِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَّقَامِيْ وَ تَذْكِيْرِيْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَعَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ فَاَجْمِعُوْۤا اَمْرَكُمْ وَشُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ اَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوْۤا اِلَيَّ وَ لَا تُنْظِرُوْنِ(یونس:۷۲) یعنی اے میری قوم اگر تمہیں میرا مرتبہ اور اللہ تعالیٰ کے نشانوں کے ذریعہ تمہیں فرائض کی ادائیگی کی طرف توجہ دلانا ناگوار گذرتا ہے تو پھر بے شک میرے مقابلہ میں نکل آؤ.اپنی تمام قوتوں کو مجتمع کر لو اور ہر لحاظ سے مجھے مٹانے کے لئے متحد ہو جاؤ پھر دیکھو کہ کون ہے جو کامیاب ہوتا ہے اور کون ہے جو ناکامی کا منہ دیکھتا ہے.بالکل اسی رنگ میں اللہ تعالیٰ اس جگہ فرماتا ہے کہ کفار اپنی تمام طاقتوں کو مجتمع کر لیں گے وہ افسر اور کمانڈر مقرر کر کے مسلمانوں کے خلاف اعلان جنگ کریں گے مگر نہ ان کے کمانڈر ان کے کام آئیں گے،نہ ان کے جیوش ان کو فتح دلائیں گے، نہ ان کے افسر ان کو کامیابی تک پہنچائیں گے اور نہ ان کے منصوبے مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکیں گے.چنانچہ باجود اس کے کہ وہ بڑے بڑے ماہر اور تجربہ کار افسر چن چن کر مقرر کیا کرتے تھے وہ افسر مسلمانوں کے مقابلہ میں ہمیشہ شکست کھا کر واپس آتے.غور کرو اورسوچو کہ کیسے نازک وقت میں اسلام کی ترقی کی یہ عظیم الشان خبر دی گئی تھی کہ یہ لوگ تو الگ رہے ان کے سردار بھی مسلمانوں کے مقابلہ میں کچھ نہیں کر سکتے.اس وقت ظاہری حالات کے لحاظ سے کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ مسلمان اپنے گھروں سے باہر نکل کر نمازیں بھی پڑھ سکیں گے فتح و غلبہ تو دور کی بات ہے مگر ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر دی گئی کہ مسلمان کامیاب ہوں گے.دشمن ناکام ہو گا اور انہیں تیز گرم پانی کے گھونٹ بار بار پینے پڑیں گے.مسلمانوں کی مظلومیت اور ان کی کمزوری اس قدر بڑھی ہوئی تھی کہ جنگ احزاب تک یہ حالت تھی جس کا حدیثوں میں ذکر آتا ہے اور قرآن کریم میں بھی اس کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے کہ منافق مسلمانوں کو طعنے دیتے تھے کہ تمہیں پاخانہ پھرنے کو تو جگہ نہیں ملتی اور فتح کی خبریں سنائی جا رہی ہیں.یہ غلبہ کی پیشگوئی چوتھے سال بعد نبوت میں کی گئی ہے اور ہجرت کے پانچویں سال تک مسلمانوں کی کمزوری کی یہ حالت تھی جس کا اوپر ذکر کیا گیا ہے.پس اتنا لمباعرصہ پہلے اسلام کے غلبہ اور مسلمانوں کی شان و شوکت کے متعلق خبر دے دینا یقیناً کسی انسان کا کام نہیں ہو سکتا.غرض لَیْسَ لَھُمْ طَعَامٌ اِلَّا مِنْ ضَرِیْعٍ لَّایُسْمِنُ وَلَا یُغْنِیْ مِنْ جُوْعٍ میں بتایا گیا ہے کہ ان کا کھانا اور ان کا پانی ان کے لئے عذاب بن جائے گا اور غم اور مصیبت ان پر نازل ہو گی.گویا استعارۃً یہ ویسا ہی کلام ہے جیسے
Page 125
اس کی ذلّت ہو گی عزّت افزائی نہیں ہو گی اور نہ کوئی یہ کہے گا کہ اسے وہ غذا دی گئی ہے جو موٹا کرتی ہے.شہاب الدین غوری نے جب ہندوستان پر حملہ کیا تو ایک جنگ میں پرتھوی راج کے مقابلہ میں اس کے لشکر کے بعض سپاہی بھاگ اٹھے.شہاب الدین غوری نے بھاگنے والوں کے متعلق حکم دیا کہ ان کے منہ پر توبڑا باندھ کر اور اس میں چنے ڈال کر ان سے کہا جائے کہ یہ چنے کھاؤ.چنانچہ ان کے منہ پر توبڑے باندھے گئے اور ان میں چنے ڈال دیئے گئے یہ بتانے کے لئے کہ یہ لوگ جانوروں سے مشابہت رکھتے ہیں.(تاریخ فرشتہ ترجمہ اردو جلد اوّل صفحہ ۲۲۰) اب کیا کوئی معقول آدمی کہہ سکتا ہے کہ وہ سپاہی اس پر بڑے خوش ہوئے ہوں گے اور کہتے ہوں گے کہ دانہ تو اچھے گھوڑے یا اچھے گدھے کو ڈالا جاتا ہے اگر ہمیں بھی دانہ ڈال دیا گیا ہے تو کیا ہوا.پس میں تو سمجھ ہی نہیں سکا کہ اس بحث کے معنے ہی کیا ہوئے.پھر یہ بحث بھی بالکل لغو ہے کہ ضریع اونٹ کو فائدہ دیتا ہے یا نہیں.اوّل تو لغت والے لکھتے ہیں کہ لَاتَقْرُبُہٗ دَابَّۃٌ لِـخُبْثِہٖ.اس کے گند اور خرابی کی وجہ سے جانور بھی اس کو نہیں کھاتا.لیکن اگر وہ کھاتا بھی ہے تب بھی مکہ والوں نے اگر یہ بات کہی تو یقیناً انہوں نے اپنے جانور ہونے کا ثبوت دیا ہے.اگر کسی آدمی کو یہ کہا جائے کہ تمہیں جانور کا کھانا ملے گا تو کیا وہ یہ کہے گا کہ مجھے بے شک دے دو کیونکہ جانور اس کے کھانے سے موٹا ہوتا ہے.پس مفسرین کا اس بحث میں پڑ جانا کہ ضریع اونٹ کو موٹا کرتا ہے یا نہیں بالکل لغو بات ہے.قرآن نے ابوجہل اور عتبہ اور شیبہ وغیرہ کا ذکر کیا ہے کہ ان کو ضریع ملے گا اونٹوں کا ذکر نہیں کیا کہ یہ بحث کی جائے کہ اونٹ تو اس کے کھانے سے موٹے ہو جاتے ہیں.اگر کسی کے ہاں کوئی چوڑھا بھی بطور مہمان آئے اور وہ اس کے سامنے بھوسہ ڈال دے یا تازہ بتازہ گھاس لا کر رکھ دے جس کے کھانے سے بیل اور بھینسیں موٹی ہوتی ہیں تو وہ خوش نہیں ہو گا بلکہ اسے اپنی انتہائی ہتک سمجھے گا.اسی طرح جب اللہ تعالیٰ یہاں آدمیوں کا ذکر کر رہا ہے تو اس بحث کا مطلب ہی کیا ہوا کہ ضریع اونٹ کو موٹا کر دیتا ہے.میں بادب ان مفسرین سے کہتا ہوں کہ یہاں آدمیوں کی بات ہو رہی ہے جانوروں کی نہیں.اگر مکہ والوں نے ایسا کہا تھا تو یقیناً انہوں نے اپنے جانور ہونے کا ثبوت دیا تھا آپ کو ان کا جواب دینے کی فکر نہ کرنی چاہیے.وُجُوْهٌ يَّوْمَىِٕذٍ نَّاعِمَةٌۙ۰۰۹ کچھ (اور) چہرے اس دن خوش بخوش ہوں گے.حلّ لُغات.نَاعِـمَۃٌ.نَاعِـمَۃٌ: نَعَمَ سے اسم فاعل مؤنث کا صیغہ ہے اور نَعَمَ الرَّجُلُ کے معنے ہیں
Page 126
رَفِہَ وہ خوشحال اور آسودہ حال ہو گیا.اور جب نَعَمَ عَیْشُہٗ کہیں تو معنے ہوتے ہیں طَابَ وَلَانَ وَ اِتَّسَعَ.یعنی اس کی زندگی عمدہ ہو گئی اور کسی تکلیف کا سامنا اسے نہ کرنا پڑا.اور ہر چیز اسے بافراغت ملنے لگی (اقرب) بحر محیط کے مصنّف نے نَاعِـمَۃٌ کے معنے حسن و نضارت والے کے کئے ہیں اور پھر لکھا ہے کہ نَاعِـمَۃٌ کے معنے مُتَنَعِّمَۃ کے بھی ہوتے ہیں یعنی یہ معنے بھی ہیں کہ ان میں حسن اور نضارت اور تازگی پائی جائے گی اور ان کے چہرے خوبصورت ہوں گے اور یہ بھی معنے ہیں کہ انہیں بڑی بڑی نعمتیں حاصل ہوں گی (البحر المحیط زیر آیت ’’وُجُوْهٌ يَّوْمَىِٕذٍ نَّاعِمَةٌ‘‘) تفسیر.کفار کے مقابل پر مومنون کی حالت کا نقشہ پہلی آیت میں وُجُوْهٌ کا ذکر تھا جن کی صفت یہ تھی کہ وہ عَامِلَۃٌ اور نَاصِبَۃٌ تھے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں یا آنے والے ماموروں کے مقابلہ میں خوب عمل کرنے والے اور تھکا دینے والی محنت کرنے والے تھے انفرادی رنگ میں بھی اور اجتماعی رنگ میںبھی.مگر اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ باوجود ان کے انفرادی اور اجتماعی مقابلوں کے یہ نہیں ہو گا کہ خدا کا رسول دب جائے یا اکیلا رہ جائے بلکہ اس کی جماعت بڑھتی چلی جائے گی اور وہ جماعت ایسی ہو گی جو دنیا میں عزت اور کامیابی حاصل کرنے والی ہو گی چنانچہ انہی کا ذکر وُجُوْهٌ يَّوْمَىِٕذٍ نَّاعِمَةٌ میں کیا گیا ہے.سردارانِ کفار کو وُجُوْهٌ اس لئے کہا گیا تھا کہ وہ ابتداء میں وُجُوْهٌ تھے گو بعد میں خَاشِعَۃٌ ہو گئے اور جو لوگ گر جائیں.لوگوں کی نگاہ میں ذلیل ہو جائیں.ان کی آواز میں کوئی اثرنہ رہے اور وہ غم والم کی آگ میں ہر وقت جلتے رہیں وہ وُجُوْهٌ نہیں رہتے.پس ان کا نام وُجُوْهٌ ان کی ابتدائی حالت کی وجہ سے رکھا گیا تھا کیونکہ شروع میں وہ واقعہ میں سردارانِ قوم میں سے تھے بڑی عزت اور وجاہت رکھتے تھے.مگر مسلمانوں کا نام وُجُوْهٌ ان کی انتہا کی وجہ سے رکھا گیا ہے.پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کام وہی اچھا ہوتا ہے جس کا انجام اچھا ہو.کافر وُجُوْهٌ بن کر اٹھے اور خَاشِعَۃٌ بن کر رہ گئے.مگر مومن گری ہوئی حالت سے اٹھے اور وُجُوْهٌ بن گئے.ہر قسم کی عزت، رتبے اور درجے ان کو حاصل ہو گئے.چنانچہ دیکھ لو کفار کی کیا حالت ہوئی اور مومن کس حالت کو پہنچ گئے.ابو جہل بڑا ذوالوجاہت تھا مگر مرا کس حالت میں؟ ایسی حالت میں کہ پندرہ پندرہ برس کے دو انصاری لڑکوں نے اس کو جنگ بدر میں مار گرایا(صحیح البخاری کتاب المغازی باب فضل من شھد بدرًا).اس کے مقابلہ میں حضرت ابوبکرؓ مکہ کے ایک معمولی تاجر تھے مگر جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمانوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کرلی اور انہیں اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا تو مکہ میں بھی کسی نے یہ خبر پہنچا دی.ایک مجلس میں بہت سے لوگ بیٹھے تھے
Page 127
حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے والد بھی اس میں موجود تھے کہ کسی نے کہا مدینہ سے خبر آئی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم فوت ہو گئے ہیں.لوگوں نے پوچھا پھر کیا ہوا؟ اس نے بتایا کہ مسلمانوں نے ایک شخص کو خلیفہ مقرر کر کے اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے.انہوں نے پوچھا کس کے ہاتھ پر بیعت کی گئی ہے؟ اس نے جواب دیا ابو بکرؓ کے ہاتھ پر.حضرت ابوبکرؓ کے والد جو اسی مجلس میں بیٹھے تھے یہ سن کر کہنے لگے کس ابوبکر کے ہاتھ پر؟ یعنی ان کے ذہن میں بھی یہ نہیں آ سکتا تھا کہ میرے بیٹے ابوبکرؓ کو بادشاہ تسلیم کر لیا جائے گا اس نے کہا ابن ابی قحافہ.یعنی تمہارے بیٹے کے ہاتھ پر بیعت کی گئی ہے.انہوں نے ایک ایک خاندان اور قبیلہ کا نام لے کر پوچھنا شروع کیا کہ کیا انہوں نے بھی بیعت کر لی ہے؟ اور اس نے جواب دیا کہ ہاں.تب بے اختیار ہو کر وہ بولے کہ اَشْھَدُ اَنْ لَّا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ وَحْدَہٗ لَاشَـرِیْکَ لَہٗ وَاَشْھَدُ اَنَّ مُـحَمَّدًا عَبْدُہٗ وَرَسُوْلُہٗ حالانکہ وہ پہلے ہی مسلمان تھے ان کے کلمہ طیبہ کے پڑھنے کے معنے ہی یہ تھے کہ یہ بھی ثبوت ہے اس بات کا کہ اسلام سچا ہے.ورنہ یہ کس طرح ہو سکتا تھا کہ ابوقحافہ کے بیٹے کے ہاتھ پر تمام قبائل عرب بیعت کر لیتے.غرض اسلام کی بدولت ایک شخص ادنیٰ حالت سے ترقی کرتا ہے اور اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ باپ کو یقین نہیں آتا کہ اسے یہ مقام حاصل ہو گیا ہے حالانکہ لوگ اپنے بیٹوں کے متعلق بڑے وسیع اندازے لگایا کرتے ہیں.کئی لوگ کہا کرتے ہیں کہ ہمارا بیٹا بڑا لائق ہے اور جب پوچھا جائے کیا لیاقت ہے؟ تو کہتے ہیں کتاب فر فر پڑھ لیتا ہے.ان کے نزدیک ایک معمولی کتاب کو پڑھ لینا بھی بہت بڑے علم کا ثبوت ہوتا ہے خواہ وہ اپنی زبان کے اشعار ہی ہوں یا خواہ فر فر بھی نہ پڑھتا ہو وہ کہیں گے یہی کہ ہمارا بیٹا بڑا لائق ہے کتاب کو فر فر پڑھ لیتا ہے.پس حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے باپ کے نزدیک ان کے بیٹے کی سب سے زیادہ قدر ہونی چاہیے تھی مگر ان کے باپ کی یہ حالت ہے کہ انہیں یقین تک نہ آیا کہ ان کے ہاتھ پر مسلمانوں نے بیعت کر لی ہے.پس ابوجہل بڑا ہو کر چھوٹا ہو گیا اور ابو بکر چھوٹا ہو کر بڑا بن گیا.یہی مفہوم ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اس الہام میں ادا کیا گیا ہے کہ ’’کئی چھوٹے ہیں جو بڑے کئے جائیں گے اور کئی بڑے ہیں جو چھوٹے کئے جائیں گے‘‘ (تذکرہ صفحہ۴۵۳ ایڈیشن چہارم) گویا ایک کی ابتدا بڑے ہونے سے ہوئی اور انتہا چھوٹے ہونے پر ہوئی اور ایک کی ابتدا چھوٹے ہونے سے ہوئی اور انتہا بڑے ہونے پر ہوئی.ایک کا وُجُوْہٌ نام رکھا گیا ہے ابتدا کی وجہ سے اور دوسرے کا وُجُوْہٌ نام رکھا گیا ہے انتہا کی وجہ سے.ورنہ ایک ملک کے وہ دونوں سردار نہیں ہو سکتے تھے وہ تو ایک دوسرے کے مدمقابل تھے.پس اس جگہ یہی بتایا گیا ہے کہ اے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرنے والو! تم آج وُجُوْہٌ ہو کل خَاشِعَۃٌ ہوجاؤ گے.مسلمان آج گرے
Page 128
ہوئے ہیں کل وُجُوْہٌ بن جائیں گے.وُجُوْهٌ يَّوْمَىِٕذٍ نَّاعِمَةٌ کے روحانی لحاظ سے معنے پھر وُجُوْہٌ کے ساتھ نَاعِـمَۃٌ کا لفظ بڑھا دیا اور نَاعِـمَۃٌ کے دو معنے بتائے جا چکے ہیں.حسن و نضارت والے اور یہ بھی کہ وہ مُتَنَعِّمَۃ ہوں گے.یعنی بڑی بڑی نعمتیں ان کو حاصل ہوں گی.ذاتی طور پر بھی وہ کمال رکھیں گے اور ماحول کے لحاظ سے بھی کمال رکھیں گے جہاں ان کو ذاتی طور پر نعمتیں حاصل ہوں گی وہاں اللہ تعالیٰ ان کو بیرونی نعمتیں بھی عطا کرے گا.ظاہری معنوں کے لحاظ سے یہ مراد ہو گی کہ وہ حسین، خوبصورت اور صاحب اموال ہوں گے اور روحانی لحاظ سے یہ معنے ہوں گے کہ وہ متقی اور صاحب علوم ہوں گے یعنی متقی بھی ہوں گے اور علومِ روحانیہ بھی ان کو حاصل ہوں گے.اپنی ذات میں بھی کامل عرفان اور استغناء ان کو حاصل ہو گا اور ان کے پاس ایسے علوم اور اموال بھی ہوں گے جو دوسروں کو سکھا سکیں اور دے سکیں.حسن ایک ذاتی چیز ہے اور مال ایسی چیز ہے جو دوسرے کو دی جا سکتی ہے.اسی طرح تقویٰ ایسی چیز ہے جو انسان کسی کونہیں دے سکتا لیکن علم ایسی چیز ہے جو دوسرے کو دے سکتا ہے.پس بتایا کہ جیسے ظاہری لحاظ سے حسن اور مال دونوں نعمتیں ان کو حاصل ہوں گی اسی طرح باطنی لحاظ سے تقویٰ بھی ان میں پایا جائے گا اور علم بھی ان کو عطا ہو گا.ظاہری لحاظ سے وُجُوْهٌ يَّوْمَىِٕذٍ نَّاعِمَةٌ کے یہ معنے ہوں گے کہ وہ اس دن بڑے حسین نظر آ رہے ہوں گے بظاہر یہ سمجھنا مشکل معلوم ہوتا ہے کہ کسی خاص وقت کوئی شخص حسین کس طرح ہو جائے گا.مگر حقیقت یہ ہے کہ جس کے ساتھ محبت کا تعلق ہو وہ بہت ہی خوبصورت دکھائی دیتا ہے اور اس آیت میں اسی طرف اشارہ ہے کہ بوجہ ذاتی تقویٰ اور احسان کے وہ لوگوں کے محبوب ہو جائیں گے اور خواہ ان کی شکل کیسی ہی ہو وہ لوگوں کو حسین نظر آئیں گے جیسے ہر باپ کو اپنا بیٹا اور ہر بیٹے کو اپنا باپ حسین نظر آتا ہے.حضرت عمرو بن العاصؓ مسلمان ہونے سے پہلے اسلام کے شدید مخالف تھے جب وہ وفات پانے لگے تو سخت گھبرا رہے تھے کہ میں اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھاؤں گا.ان کے بیٹے نے کہا کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ کو تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بڑی بڑی خدمتوں کے مواقع ملے ہیں انہوں نے کہا ہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بے شک خدمتوں کے مواقع ملے تھے مگر آپ کے بعد جن حالات میں سے ہم گذرے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ڈر آتا ہے کہ نامعلوم اللہ تعالیٰ ہم سے کیا معاملہ کرے.پھر کہنے لگے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر کوئی حلیہ مجھ سے پوچھے تو میں نہیں بتا سکتا آپ کے متعلق مجھ پر دو زمانے گذرے ہیں ایک وقت تو وہ تھا جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کیا ا ور مجھے اس دعویٰ سے اس قدر نفرت پیدا ہوئی کہ میں نے اس دن کے بعد
Page 129
آپ کی شکل کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا.پہلے تو آپ سے کوئی زیادہ واقفیت ہی نہیں تھی کہ شکل یاد ہوتی.دعویٰ کے بعد یہ حالت ہو گئی کہ آپ سامنے سے آرہے ہوتے تو میں اپنی آنکھیں نیچی کر لیتا کہ نعوذ باللہ آپ کی شکل کو میں نہ دیکھ لوں.اس کے بعد جب مجھے ایمان نصیب ہوا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھے وہ جلال، وہ حسن اور وہ نور نظر آیا کہ اس کے بعد مجھے جرأت ہی نہیں ہوئی کہ میں آپ کے چہرہ پر نظر ڈال سکوں.چنانچہ آج اگر مجھ سے کوئی شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم کا حلیہ دریافت کرے تو میں اسے نہیں بتا سکتا.کیونکہ کفر کی حالت میں آپ کی شکل سے زیادہ بد صورت مجھے کوئی اور شکل نظر نہیں آتی تھی اور ایمان کی حالت میں آپ کی شکل سے زیادہ خوبصورت مجھے کوئی اور شکل نظر نہیں آتی تھی اس لئے دونوں حالتوں میں مَیں آپ کو دیکھ نہ سکا.گویا کفر کی حالت میں انتہائی نفرت کی وجہ سے نہ دیکھ سکے اور ایمان کی حالت میں آپ کے جلال اور آپ کے حسن کو برداشت کرنے کی طاقت نہ رکھنے کی وجہ سے نہ دیکھ سکے (صحیح مسلم کتاب الایمان باب کون الاسلام یـھدم ما قبلہ).وُجُوْهٌ يَّوْمَىِٕذٍ نَّاعِمَةٌ کے ظاہری معنے حقیقت یہی ہے کہ ایک ہی چیز کو انسان بعض حالات میں اچھا اور بعض حالات میں برا سمجھنے لگ جاتا ہے اور محبت یا نفرت کی وجہ سے شکلیں بھی بدل جاتی ہیں.ہم نے بیسیوں میاں بیوی کی لڑائیاں دیکھی ہیں پہلے وہ ایک دوسرے کے عاشقِ زار ہوتے ہیں اور میاں سمجھتا ہے کہ خدا نے مجھے دنیا کی حسین ترین بیوی عطا فرمائی ہے مگر جب لڑائی ہو جاتی ہے تو خاوند کہتا ہے کہ اس کی شکل ہی اتنی بری ہے کہ دیکھنے کے قابل ہی نہیں.غرض نَاعِـمَۃٌ کے اگر ظاہری معنے لئے جائیں تو وُجُوْهٌ يَّوْمَىِٕذٍ نَّاعِمَةٌ کا مفہوم یہ ہو گا کہ وہ ایسے مقبولِ جہاں ہو جائیں گے کہ لوگوں کو حسین نظر آنے لگ جائیں گے.یہ ضروری نہیں کہ ان کی شکلیں بھی حسین ہوں بلکہ وہ دنیا کو حسین اور خوبصورت معلوم ہونے لگ جائیں گے.جب وہ دنیا کے محسن ہوں گے، جب وہ خدمت خلق کرنے والے ہوں گے، جب وہ یتامیٰ سے حُسنِ سلوک کرنے والے ہوں گے، جب وہ غریبوں سے ہمدردی کرنے والے ہوں گے، جب وہ گرے ہوئے لوگوں کو اٹھانے والے ہوں گے تو وہ لوگ دنیا کو تمام دوسرے لوگوں کی نسبت زیادہ خوبصورت اور اچھے نظر آنے لگ جائیں گے اور دوسرے لوگوں کے چہرے ان کے مقابلہ میں انہیں حسین نظر نہیں آئیں گے.پس اگر ہم اس کے ظاہری معنے لیں تب بھی وہ صحیح ہوں گے مگر اس طرح نہیں کہ ان کی شکلیں خوبصورت ہو جائیںگی بلکہ جیسے محاورہ کے طور پر کہتے ہیں پرنالہ چلتا ہے اور مراد یہ ہوتا ہے کہ پرنالہ میں پانی چلتا ہے اسی طرح اس کا یہ مطلب ہو گا کہ وہ اپنے احسان کی وجہ سے حسین نظر آنے لگ جائیں گے.جب ان میں احسان کا مادہ ہو گا ، جب ان میں نیکی ہو گی، جب ان میں عفت ہو گی، جب ان میں
Page 130
حُسنِ سلوک کا جذبہ ہو گا تووہ لوگوں کو بے انتہا پیارے لگنے لگ جائیں گے پس وُجُوْهٌ يَّوْمَىِٕذٍ نَّاعِمَةٌ میں صحابہ کے یا مومنوں کے اخلاق فاضلہ کی طرف اشارہ ہے یعنی ایسے اعلیٰ درجہ کے اخلاق اور حسنِ سلوک کی خدا ان کو توفیق عطا فرمائے گا کہ وہ دنیا کی نگاہ میں بڑے خوبصورت اور حسین نظر آئیں گے اور اگر اس سے تقویٰ اور علم مراد ہو تو وہ ظاہر ہی ہے اس کی تشریح کی ضرورت نہیں.لِّسَعْيِهَا رَاضِيَةٌۙ۰۰۱۰ اپنی (سابقہ) کوششوں پر مطمئن ہوں گے.تفسیر.دنیا میں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان دوسرے سے حسنِ سلوک کرتا ہے مگر وہ اپنے کئے پر خوش نہیں ہوتا جیسے ریاء والا ہوتا ہے کہ وہ بعض دفعہ ہزاروں لاکھوں روپیہ بھی چندہ میں دے دیتا ہے اور لوگ اسے دیکھ کر کہتے ہیں سبحان اللہ واہ واہ اس نے کتنی بڑی قربانی کا نمونہ دکھایا مگر اس کا دل اندر سے خون ہو رہا ہوتا ہے یا وہ دکھاوے کے لئے صدقہ کرتا ہے تو لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں مگر اس کی جان اندر سے ہلکان ہو رہی ہوتی ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنے روپے کو ضائع کیا ہے.تو صرف ظاہر میں تعریف کا ہو جانا اور لوگوں کی نگاہ میں حسین بن جانا کافی نہیں ہوتا بلکہ اپنی نگاہ میں بھی حسین بننا ضروری ہوتا ہے.لوگوں کی نگاہ میں تو ایک ریاکار بھی حسین ہو جاتا ہے مگر وہ اپنے دل میں جل رہا ہوتا ہے کہ میں تباہ ہو گیا.لیکن فرماتا ہے وہ ایسے کامل وجود ہوں گے کہ ان میں یہ نقص نہ ہو گا.چنانچہ وُجُوْهٌ يَّوْمَىِٕذٍ نَّاعِمَةٌ لِّسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ کا اگر ہم معنوی لحاظ سے ترجمہ کریں تو یوں ہو گا کہ کچھ چہرے ایسے ہوں گے یا کچھ افراد ایسے ہوں گے کہ ایک دن آئے گا جب کہ وہ دنیا کی نگاہ میں حسین ہو جائیں گے لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ اور اپنی نگاہ میں بھی حسین ہوں گے اور وہ اپنے کئے پر خوش ہوں گے ان میں یہ احساس نہیں ہو گا کہ ہم نے لوگوں کے لئے قربانی کر کے اپنے اوپر ظلم کیا ہے بلکہ وہ جس قدر خدمات سرانجام دیں گے، جس قدر قربانیاں کریں گے، جس قدر احسانات کریں گے ان کے دل اور زیادہ خوش ہوں گے.گویا ایمان اور اخلاص اور محبت باللہ سے ان کے قلوب اس طرح پُر ہوں گے کہ صرف لوگ ہی ان کو دیکھ کر خوش نہیں ہوں گے بلکہ وہ خود بھی اپنے کاموں کو دیکھ کر خوش ہوں گے.یہ ویسی ہی بات ہے جیسے محاورہ کے طور پر کہا جاتا ہے کہ اگر مجھے پھر موقع ملے تو میں پھر بھی یہی کام کروں گا.بعض دفعہ ایک انسان ایک کام تو کر لیتا ہے مگر بعد
Page 131
میں اپنے کئے پر نادم اور پشیمان ہوتا ہے اور اس کی ضمیر اسے ملامت کرتی ہے چنانچہ جب اسے کہا جائے کہ کیا اب جب کہ تم وہ کام کر چکے ہو اور وہ موقع گذر چکا ہے کیا تمہارے دل کو اطمینان ہے کہ تم نے جو کچھ کیا تھا درست کیا تھا؟ تو وہ بسا اوقات کہتا ہے کہ نہیں.میں اپنے کام پر نادم ہوں اور مجھے اعتراف ہے کہ میں نے درست کام نہیں کیا.لیکن اگر اس کے ضمیر کو تسلی ہوتی ہے اور وہ اپنے بیان میں سچ سے بھی کام لیتا ہے تو وہ کہتا ہے اگر میں پھر انہی حالات میں ڈالا جاؤں تو میں پھر بھی یہی کام کروں گا یعنی باوجود اس کے کہ زمانہ گذر چکا ہے میرے دل کو اس قدر اطمینان ہے کہ اگر پھر ویسے ہی حالات پیدا ہوں تو میں پھر بھی وہی کام کروں گا.دنیا میں ہر چیز کو دو نقطہ ہائے نگاہ سے دیکھا جاتا ہے.بعض دفعہ ماضی سے استقبال کی طرف دیکھا جاتا ہے اور بعض دفعہ حال سے ماضی کی طرف دیکھا جاتا ہے.یہ الگ الگ نقطہ ہائے نگاہ ہوتے ہیں.کبھی ہم ماضی سے مستقبل کی طرف دیکھتے ہیں تو ایک چیز ہمیں اچھی معلوم ہوتی ہے مگر جب وہ استقبال ماضی میں بدل جاتا ہے اور ہم غور کرتے ہیں تو وہ فعل ہمیں برا محسوس ہونے لگتا ہے لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم ماضی سے مستقبل کے نتیجہ کو دیکھتے ہیں اس وقت بھی وہ ہمیں اچھا معلوم ہوتا ہے اور جب وہ وقت گذر جاتا ہے نتائج روشن ہو جاتے ہیں اور ہم حال سے ماضی کی طرف دیکھتے ہیں تب بھی وہ کام ہمیں اچھا معلوم ہوتا ہے.جو کام اعلیٰ درجے کا ہو اس کی علامت یہی ہے کہ اسے ماضی سے استقبال کے نقطہ نگاہ سے دیکھیں تب بھی وہ اچھا معلوم دے اور جب حال سے ماضی کی طرف دیکھا جائے تب بھی وہ اچھا معلوم دے.اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ مسلمان ماضی کے مقام پر کھڑے ہو کر جب استقبال کی طرف دیکھیں گے تب بھی ان کو وہ اعمال جن کے کرنے کا انہوں نے تہیہ کیا ہے خوبصورت نظر آئیں گے اور جب وہ ان کاموں کو کر چکیں گے اور مستقبل کے مقام پر کھڑے ہو کر ماضی کی طرف دیکھیں گے تب بھی ان کو وہ اعمال خوبصورت نظر آئیں گے گویا آگے اور پیچھے دونوں طرف ان کے حُسن ہی حُسن ہو گا.یہ ایسی ہی بات ہے جیسے گھوڑا خریدنے والے کبھی اس کو سامنے کی طرف سے دیکھتے ہیں اور کبھی اس کو پیچھے کی طرف سے دیکھتے ہیں.بعض جانور سامنے سے تو خوبصورت معلوم ہوتے ہیں مگر وہ پیچھے سے بدصورت نظر آتے ہیں اور بعض پیچھے کی طرف سے خوبصورت نظر آتے ہیں اور سامنے سے بدصورت نظر آتے ہیں.اچھا جانور وہی ہوتا ہے جو سامنے سے بھی اچھا نظر آئے اور پیچھے کی طرف سے بھی اچھا نظر آئے.انسانی اعمال کی بھی یہی دو حالتیں ہوتی ہیں بعض دفعہ ایک کام کرنے سے پہلے بھی اچھا معلوم ہوتا ہے اور کرنے کے بعد بھی اچھا معلوم ہوتا ہے اور بعض دفعہ ایک کام کرنے سے پہلے خوبصورت نظر آتا ہے اور کرنے کے بعد برا معلوم
Page 132
ہوتا ہے اور بعض دفعہ ایک کام کرنے سے پہلے برا معلوم دیتا ہے اور کرنے کے بعد اچھا.اگر کوئی کام کرنے سے پہلے بھی اچھا نظر آئے اور کرنے کے بعد بھی اچھا نظر آئے تو وہی کام قابلِ قدر ہوتا ہے جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی جنگ میں شہید ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے خوش ہو کر فرمایا جو کچھ مجھ سے مانگنا چاہتے ہو مانگو میں تمہاری ہرخواہش پوری کرنے کے لئے تیار ہوں.اگر انہوں نے علیٰ وجہ البصیرت شہادت کو قبول نہ کیا ہوتا تو وہ کہتے کہ خدایا میری خواہش یہ ہے کہ تو مجھے زندہ کر دے میں نے بے وقوفی کی جو جنگ میں شامل ہوا اور مارا گیا اب تو مجھے پھر زندہ کر دے تا کہ میں اپنے بیوی بچوں کے پاس جاؤں مگر انہوں نے یہ نہیں کہا کیونکہ انہوں نے جب شہادت کو مستقبل کے افق میں دیکھا تھا تب بھی یہ نتیجہ نکالا تھا کہ یہ اچھی چیز ہے اور جب اس درجہ کو پالیا اور ماضی کی طرف نگاہ دوڑاتے ہوئے اپنی شہادت کو دیکھا تو اس وقت بھی انہوں نے یہی نتیجہ نکالا کہ یہ اچھی چیز ہے چنانچہ انہوں نے کہا یا اللہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ تو مجھے زندہ کر دے تا کہ میں پھر تیری راہ میں شہید ہو جاؤں (ترمذی کتاب التفسیـر باب سورۃ اٰل عـمران) گویا مرنے کے بعد بھی انہوں نے اپنی شہادت کو اچھی نگاہ سے دیکھا.تو کام کو شروع کرنے سے پہلے اور اس کے ختم ہونے کے بعد دونوں نقطہ ہائے نگاہ سے دیکھنے کے نتیجہ میں ہی کسی کام کی حقیقی خوبی ظاہر ہوتی ہے اور لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ میں اسی مضمون کی طرف اشارہ ہے جہاں لوگ ان کو حسین پائیں گے وہ اپنے آپ کو بھی حسین پائیں گے یہ نہیں ہو گا کہ وہ بعد میں کہیں ہم نے بہت برا کیا بلکہ کام کرنے سے پہلے بھی وہ اپنے اعمال کو اچھا سمجھتے تھے اور کام کرنے کے بعد بھی ان کو اپنے اعمال خوبصورت نظر آئیں گے.اپنے آپ کو حسین پانے کے معنے اس متکبّرانہ خیال کے نہیں جو ہر بے وقوف میں پایا جاتا ہے کہ ہم چومن دیگرے نیست کی مرض میں مبتلا ہوتا ہے یہ حالت تو نہایت خراب اور دل کی بیماری پر دلالت کرتی ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سچے غور اور فکر اور نتائج اعمال دیکھ کربھی وہ اپنے اعمال کو اچھا پائیں گے اور یہ مقام کامل کا مقام ہوتا ہے.فِيْ جَنَّةٍ عَالِيَةٍۙ۰۰۱۱ بلند (وبالا) جنت میں (رہ رہے) ہوں گے.تفسیر.فرماتا ہے جب وہ لوگوں کی نگاہوں میں خوبصورت ہو جائیں گے اور اپنی نظروں میں بھی وہ حسین دکھائی دیں گے.جب وہ ماضی سے استقبال کی طرف دیکھیںگے تب بھی وہ ان افعال پر خوش اور مطمئن
Page 133
ہوں گے جن کے کرنے کا انہوں نے ارادہ کیا ہے اور جب وہ حال سے ماضی کی طرف نگاہ دوڑائیں گے تب بھی انہیں اپنے افعال پر اطمینا ن ہو گا.پس دنیا کی رائے بھی ان کے متعلق اچھی ہو گی اور ان کی اپنی رائے بھی اپنے متعلق اچھی ہو گی بلکہ یوں کہو کہ انعامات چونکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ملتے ہیں اور سب تعریفیں اسی کی طرف سے آتی ہیں اس لئے خدا کی رائے بھی ان کے متعلق اچھی ہو گی پبلک کی رائے بھی ان کے متعلق اچھی ہو گی اور ان کی اپنی رائے بھی اپنے متعلق اچھی ہو گی اور یہی انسانی اعمال کے تین اہم ترین حصے ہیں یعنی انسان کا اپنی ذات سے معاملہ، انسان کا بنی نوع انسان سے معاملہ اور انسان کا خدا تعالیٰ سے معاملہ.اپنی ذات سے ان کا معاملہ ایسا ہو گا کہ ان کی اپنی رائے اپنے متعلق اچھی ہو گی.بنی نوع انسان سے ان کا معاملہ ایسا ہو گا کہ پبلک کی رائے ان کے متعلق اچھی ہو گی اور خدا تعالیٰ سے ان کا معاملہ ایسا ہو گا کہ خد اتعالیٰ کی رائے ان کے متعلق اچھی ہو گی.جب یہ تینوں تعریفیں کسی کو حاصل ہو جائیں تو اس میں کیا شبہ ہے کہ وہ فِیْ جَنَّۃٍ عَالِیَۃٍ کا مصداق ہوتا ہے.لوگوں میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور جہاں جاتا ہے لوگ اسے اپنی آنکھوں پر بٹھاتے ہیں خواہ مالی لحاظ سے اس کے پاس ایک پیسہ تک نہ ہو.اس کے کپڑے پھٹے پرانے ہوں لیکن وہ خود اپنے نفس میں بھی اپنے آپ کو بلند پاتا ہے دنی نہیں پاتا بلکہ سمجھتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے اخلاقی لحاظ سے مجھے بلند مرتبہ دیا ہے ذلیل لوگوںمیں مجھے شامل نہیں کیا.اور لوگ بھی اس کی عزت کرنے پر مجبور ہوتے ہیں.جَنَّۃٍ عَالِیَۃٍ سے مراد ایسے باغات جو اونچی جگہ ہوں پرانے زمانہ میں شاید جَنَّۃٍ عَالِیَۃٍ کا مفہوم پوری طرح نہ سمجھا جاتا ہو مگر اس زمانہ میں اس کا مفہوم سمجھنا بالکل آسان ہے کیونکہ ہینگنگ گارڈنز (HANGING GARDENS) دنیا میں پائے جاتے ہیں اور بمبئی میں بھی ایسے کئی باغات ہیں میں اوائل عمر میں ایک دفعہ بمبئی گیا وہاں مجھے بتایا گیا کہ یہاں ہینگنگ گارڈنز ہیں.مجھے خیال ہوا کہ شاید کھمبوں میں گملے لٹکا کر باغات بنائے گئے ہوں گے یا کسی چٹان پر جو آگے بڑھی ہو گی اور ہوا میں معلّق نظر آتی ہوگی.مگر جب مجھے کوئی ایسا باغ وہاں نظر نہ آیا تو میں نے کسی سے پوچھا کہ لوگ تو کہتے تھے یہاں ہینگنگ گارڈنز ہوتے ہیں مگر مجھے تو کوئی نظر نہیں آیا.اس پر اس نے بتایا کہ ہینگنگ گارڈنز تو ابھی آپ دیکھ کر آئے ہیں تب مجھے پتہ لگا کہ ہینگنگ گارڈن کا یہ مطلب نہیں کہ وہ لٹکا ہوا ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ وہ اونچی چوٹی پر ہے اور چونکہ لوگ نیچے ہوتے ہیں اور باغات چوٹی پر ہوتے ہیں اس لئے ان کو ہینگنگ گارڈنز کہا جاتا ہے یعنی بلند اور اونچے باغات.اسی طرح فرماتا ہے مومن ایسے باغات میں ہوں گے جو اونچے اور بلند ہوں گے.جنت کے معنے سایہ دار جگہ کے ہیں اور
Page 134
عالیہ کے معنے بلند کے ہیں.جو چیز سایہ دار ہو اس کی اندر کی چیزیں لوگوں کو نظر نہیں آتیں اور جو چیز بلندی پر ہو اس پر دھوپ پڑتی ہے سایہ دار نہیں رہ سکتی.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جن باغات کا ہم ذکر کرتے ہیں ان کے اندر دونوں قسم کی خوبیاں پائی جائیں گی جہاں تک شہرت اور عزت کا سوال ہے وہ عالیہ ہوں گے اور جہاں تک ان کی نیکیوں اور خوبیوں کا سوال ہے وہ سایہ دار ہوں گے یعنی لوگوں کی نظریں بھی ان کی طرف اٹھیں گی اور پھر وہ تمازت اور دھوپ کا شکار بھی نہیں ہوں گے بلکہ ہر وقت سایۂ رحمتِ الٰہی کے نیچے رہیں گے ورنہ اکثر لوگ بلندی پر پہنچ کر ننگے ہوجاتے ہیں اور خدا تعالیٰ کے فضل کا سورج بجائے ان کے لئے نفع مند ہونے کے ان کے جلانے کا موجب ہو جاتا ہے.لَا تَسْمَعُ فِيْهَا لَاغِيَةًؕ۰۰۱۲ وہ اس میں کوئی لغو بات نہ سنیں گے.حلّ لُغات.لَاغِیَۃٌ.لَاغِیَۃٌ کے معنے ہیں اَللَّغْوُ یعنی لغو اور بے ہودہ بات.کہتے ہیں کَلِمَۃٌ لَاغِیَۃٌ اَیْ فَاحِشَۃٌ.کَلِمَۃٌ لَاغِیَۃٌ ایسے کلمہ کو کہتے ہیں جو فحش اور برا ہو وَمِنْہُ ’’.لَاتَسْمَعُ فِیْـھَا لَاغِیَۃً.‘‘ اَیْ کَلِمَۃً ذَاتَ لَغْوٍ اور لَاتَسْمَعُ فِیْھَا لَاغِیَۃً کے یہ معنے ہیں کہ تو اس میں کوئی فحش اور بری بات نہیں سنے گا یا وہ چہرے اس میں کوئی لغو بات نہ سنیں گے.(اقرب) تفسیر.لَاغِیَۃً سننے کی دو وجوہات اور مومنوں کا ان سے پاک ہونا دنیا میں انسان دو۲ ہی طرح بری باتیں سنتا ہے یا تو اس طرح کہ وہ خود کج رو ہوتا ہے اور لوگوں سے لڑتا رہتا ہے اس کے نتیجہ میں لازمی طور پر اسے لَاغِیَۃ سننا پڑتا ہے مثلاً جب وہ دوسرے کو خبیث کہے گا تو خبیث کا لفظ اس کے اپنے کان میں بھی پڑے گا اور اس طرح اسے لَاغِیَۃ سننا پڑے گا اور یا پھر دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ لوگ اس سے لڑتے ہیں اور وہ لَاغِیَۃ سنتا ہے.اپنا کہا انسان تب سنتا ہے جب وہ لوگوں سے خوش نہ ہو اور لوگوں سے لَاغِیَۃ تب سنتا ہے جب لوگ اس سے خوش نہ ہوں مگر فرماتا ہے وہ لوگ ایسے ہوں گے کہ لَاغِیَۃ نہیں سنیں گے یعنی وہ لوگوں سے خوش ہوں گے اور لوگ ان سے خوش ہوں گے ان میں رحم ہو گا، ان میں ہمدردی ہو گی، ان میں پردہ پوشی کی عادت ہو گی، ان میں حسنِ سلوک کا جذبہ ہو گا، ان میں محبت ہو گی، ان میں خلوص ہو گا اور اس وجہ سے وہ لوگوں سے لڑیں
Page 136
انہیں برا کہیں بلکہ وہ لوگوں کے محسن ہوں گے، منعم ہوں گے، معلّم ہوں گے اور لوگ ان کی تعریف کریں گے.لیکن کمینے انسان کی یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ دونوں حالتوں میں لڑتا ہے اس پر احسان کرو تب بھی لڑتا ہے نہ کرو تب بھی لڑتا ہے.گویا اس کی حالت کتے کی طرح ہوتی ہے کہ اِنْ تَحْمِلْ عَلَیْہِ یَلْھَثْ اَوْتَتْرُکْہُ یَلْھَثْ (الاعراف:۱۷۷) دونوں حالتوں میں زبان نکالے کتے کی طرح پیچھے پڑا رہتا ہے.ایسا انسان اسی صورت میں خاموش ہوتا ہے جب اس کے مدمقابل کو حکومت اور غلبہ میسر آ جائے.پس فرماتا ہے مسلمانوں کو غلبہ مل جائے گا اور کوئی صورت لَاغِیَۃً سننے کی نہیں رہے گی دشمنانِ دین جو احسان فراموش ہیں وہ غلبہ کی وجہ سے تعریف کریں گے اور جو شرافت رکھتے ہیں وہ احسان کی وجہ سے تعریف کریں گے اور یہ خود نیک طبیعت ہونے کی وجہ سے کسی سے بدگوئی نہیں کریں گے اس لئے لغو ان کو سنائی ہی نہیں دے گا.فِيْهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌۘ۰۰۱۳ اس میں ایک بہتاہوا چشمہ ہوگا.تفسیر.عَيْنٌ جَارِيَةٌ سے مراد ایسا کام جو ہمیشہ ہمیش کے لئے چلتا چلا جائے مومن جس جنّت میں رہیں گے اس میں ایک جاری چشمہ ہو گا.اگلے جہان میں تو یہ ہو گا ہی.اس کے متعلق کسی تفصیل کی ضرورت نہیں.نہ میں نے اسے دیکھا ہے اور نہ کسی اور نے، یہ ایک ایمانی معاملہ ہے.لیکن دنیا کے لحاظ سے یہ معنے ہیں کہ وہ ایسے علوم اپنے ورثہ میں چھوڑیں گے اور ایسے سلوک بنی نوعِ انسان سے کریں گے جن کا اثر عرصۂ دراز تک چلتا چلا جائے گا.کچھ لوگوں کا احسان صرف وقتی ہوتا ہے لیکن کچھ لوگوں کا احسان صدقۂ جاریہ کا رنگ اپنے اندر رکھتا ہے مثلاً کسی غریب کو ایک پیسہ دے دینا یہ بھی احسان ہے مگر جب وہ اس پیسے سے روٹی خرید کر کھا لیتا ہے تو اس احسان کا دائرہ ختم ہو جاتا ہے لیکن ایک احسان یہ ہے کہ کسی کو دین کی باتیں سکھائی جائیں یا اخلاقی لحاظ سے اعلیٰ تربیت دی جائے یہ احسان بڑا وسیع ہے یا مثلاً کسی کو کوئی پیشہ سکھا دینا یا کسی کو پیشہ چلانے کے لئے مدد دے دینا یا اسے اپنے پیشہ کے چلانے کے لئے ہتھیار خرید دینا یہ احسان اپنے اندر بہت بڑی وسعت رکھتا ہے.روٹی دے دینا اور قسم کا احسان ہے اور پیشہ سکھا دینا یا پیشہ کے چلانے کے لئے روپیہ سے امداد کرنا یا ہتھیار وغیرہ خرید دینا یہ اور قسم کا احسان ہے پہلی قسم کا صدقہ ختم ہو گیا مگر یہ صدقہ صدقہ جاریہ ہے فِیْھَا عَیْنٌ جَارِیَۃٌ سے
Page 137
یہی مراد ہے کہ ان کے صدقات صدقاتِ جاریہ ہوں گے اور ان کے احسان بنی نوع انسان سے محدود نہیں ہوں گے یا معمولی اور چھوٹے درجہ کے نہیں ہوں گے.بلکہ ایسے ہوں گے جو عرصۂ دراز تک چلتے چلے جائیں گے.جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم سے صحابہؓ نے علم لیا.اور پھر اسے دنیا میں اس طرح پھیلایا کہ عَنْ فُلَانٍ عَنْ فُلَانٍ کے ایک لمبے سلسلہ کے ماتحت وہ اگلی نسلوں تک پہنچ گئے.اگلوں نے اگلوں تک اور پھر اگلوں نے اگلوں تک یہاں تک کہ وہ سارے علوم ہم تک پہنچ گئے.اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام میں یہ خوبی بدرجہ اتم رکھی ہوئی تھی کہ وہ علوم کے خزانے صرف اپنے تک محدود نہیں رکھتے تھے بلکہ دوسروں تک عَیْنٌ جَارِیَۃٌ بن کر پہنچا دیتے تھے.لوگوں کے پاس علم ہوتا ہے تو وہ اس کو بند کر لیتے ہیں مگر صحابہؓ کی یہ حالت تھی کہ ایک صحابیؓ سے ایک دفعہ کسی نے کوئی بات پوچھی.اس نے جواب دیا کہ مجھے تو یہ بات معلوم نہیں لیکن اگر مجھے معلوم ہوتی اور میری گردن پر کوئی شخص تلوار رکھ کر کہتا کہ اب میں تجھے قتل کرنے لگا ہوں تو میں اس کی تلوار چلنے سے پہلے جلدی جلدی بتا دیتا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم سے میں نے فلاں فلاں بات سنی ہوئی ہے(صحیح بخاری کتاب العلم باب العلم قبل القول والعمل).یہ عَیْنٌ جَارِیَۃٌ ہی تھے کہ کسی جگہ ٹکتے نہیں تھے بلکہ بہتے چلے جاتے تھے.پھر عَیْنٌ جَارِیَۃٌ میں یہ خبر بھی دی گئی تھی کہ صحابہؓ اور ان کے شاگرد دور دور تک نکل جائیں گے صرف عرب میں محدود نہیں رہیں گے.عَیْنٌ جَارِیَۃٌ کے ماتحت مسلمانوں کا مختلف ممالک میں پھیل جانا چنانچہ دیکھ لو مسلمان عرب سے نکلے اور دنیا کے دور دراز ممالک تک پھیل گئے یہاں تک کہ وہ چین بھی گئے اور انہوں نے اسلام پھیلایا.انطاکیہ میں بھی گئے اور اسلام پھیلایا.سپین میں بھی گئے اور اسلام پھیلایا.غرض وہ دنیا کے کناروں تک نکل گئے اور دنیا میں علوم کے دریا انہوں نے بہا دیئے.جس طرح جاری چشمہ کا پانی دور دور کی زمین کو سیراب کر دیتا ہے اسی طرح مسلمان ٹھہرتے نہیں تھے بلکہ اپنے علوم سے دنیا کو مستفیض کر تے چلے جاتے تھے.یہی خوبیاں ہیں جو جیتنے والی اقوام سے مخصوص ہیں.ہماری جماعت کو سوچنا چاہیے کہ کیا ہم میں بھی یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں یا نہیں.حکومت کا حصہ تو اپنے وقت پر آئے گا لیکن سوال یہ ہے کہ کیا باقی خوبیاں ہم نے اپنے اندر پیدا کر لی ہیں؟ کیا ہم اپنی نظر میں، لوگوں کی نظر میں اور پھر خدا تعالیٰ کی نظر میں ہر قسم کے نقائص سے پاک ہیں؟ کیا ہمارے اخلاق اس قسم کے ہیں کہ ہم نہ اپنی زبان سے لَاغِیَۃ سنتے ہیں اور نہ لوگوں کی زبان سے لَاغِیَۃ سنتے ہیں؟ اور کیا ہماری کوششیں یہی ہوتی ہیں کہ عَیْنٌ جَارِیَۃٌ کی طرح ہم جو بات بھی سنیں اسے دوسرے لوگوں تک پہنچا دیں یا ہم صرف واہ واہ اور سبحان اللہ کہنے کے لئے سنتے ہیں؟ صحابہؓ کی یہ حالت تھی کہ وہ رات اور دن تعلیم میں لگے رہتے تھے اور
Page 138
پھر جو کچھ سیکھتے اسے اپنے سینوں میں ہی نہ رکھتے بلکہ لوگوں تک پہنچا دیتے.گویا وہ ایک جاری چشمہ تھا جو دنیا کو سیراب کررہا تھا.کتنی زبردست خواہش دوسروں تک علوم پہنچانے کی ہے جو اس صحابی کے دل میں پائی جاتی تھی جس نے کہا کہ اگر تلوار میری گردن پر چل رہی ہو تو اس وقت میری آخری خواہش یہ ہوگی کہ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم کی کوئی بات بیان کرنی مجھ سے رہ گئی ہو تو میں اسے جلدی جلدی بیان کر دوں.یہی خوبی ہماری جماعت کو اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے اور اپنے آپ کو علوم کے لحاظ سے عَیْنٌ جَارِیَۃٌ ثابت کرنا چاہیے.فِيْهَا سُرُرٌ مَّرْفُوْعَةٌۙ۰۰۱۴ (اور) اس میں اونچے تخت (بھی) رکھے ہوں گے.حلّ لُغات.سُرُرٌ.سُرُرٌ: سَـرِیْرٌ کی جمع ہے اور سُرُرٌ کی بجائے اَسِـرَّۃٌ بھی جمع کے طور پر استعمال ہوتا ہے اس کے معنے تخت کے ہوتے ہیں خصوصاً یہ لفظ بادشاہ کے تخت کے لئے بولا جاتا ہے چنانچہ کہتے ہیں زَالَ عَنْ سَـرِیْرِہٖ وہ اپنے سریر سے ہٹ گیا اور مراد یہ ہوتی ہے کہ ذَہَبَ عِزُّہٗ وَنِعْمَتُہٗ اس کی عزت اور دولت جاتی رہی سُـمِّیَ بِہٖ لِاَنَّ مَنْ جَلَسَ عَلَیْہِ مِنْ اَھْلِ الرِّفْعَۃِ وَالْـجَاہِ یَکُوْنُ مَسْـرُوْرًا سریر کا لفظ اس لئے استعمال کیا جاتا ہے کہ مال دار اور جاہ وجلال کے مالک لوگ تخت پر بیٹھتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں.پس چونکہ اس مقام کا حصول دل میں سرور پیدا کرتا ہے اس لئے تخت کا نام ہی سریر رکھ دیا گیا.(اقرب) مَرْفُوْعَۃٌ.مَرْفُوْعَۃٌ: رَفَعَ سے ہے اور رَفَعَہٗ کے معنے ہوتے ہیں اس نے کسی چیز کو بلند کیا (اقرب) یہ بلندی خواہ اونچا بنانے کے لحاظ سے ہو جیسے کہتے ہیں مینار اونچا بنایا گیا اور خواہ اونچا کرنے کے لحاظ سے ہو جیسے کسی چیز کو اٹھا کر اونچا کیا جاتا ہے.دونوں رنگ میں اس لفظ کا استعمال ہو جاتا ہے.مثلاً کہتے ہیں دیوار اونچی ہے اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ لمبی چلی جاتی ہے اور قامت کے اعتبار سے بلند ہے یا کہتے ہیں چھت اونچی ہے اور مراد یہ ہوتی ہے کہ زمین اور چھت میں فاصلہ زیادہ ہے گویا قامت کی بلندی ہو یا فاصلہ کی زیادتی دونوں پر رفع کا لفظ اطلاق پاتا ہے.پس مَرْفُوْعَۃٌ کے معنے ہوں گے اونچے کئے ہوئے.بلند کئے ہوئے.تفسیر.سُرُرٌ مَّرْفُوْعَةٌ کے دو معنے اس آیت کے ایک معنے یہ ہیں کہ وہ بلند شان والے ہوں گے.کیونکہ سُرُرٌ کے ساتھ مَرْفُوْعَۃٌ ہونا زیادہ شان اور عزت پر دلالت کرتا ہے.لیکن اس کے یہ
Page 139
بھی معنے ہیں کہ وہ بلند رکھے گئے ہوں گے گویا دونوں قسم کی خوبیاں ان میں پائی جاتی ہوں گی.مومنوں کی یہ شان بھی ہو گی کہ وہ نیک اعمال میں ترقی کرتے جائیں گے اور دوسروں سے نیکی میں بلند قامت ہونے کی کوشش کریں گے اور وہ اس لحاظ سے بھی مَرْفُوْعَۃٌ ہوں گے کہ خدا تعالیٰ ان کو اپنی طرف اٹھا لے جائے گا.گویا جہاں تک ان کا انسانوں سے واسطہ ہے وہ دوسرے بنی نوع انسان سے بلند قامت ہوں گے اور نیکی اور تقویٰ کے لحاظ سے اس قدر فائق ہوں گے کہ ان میں اور عام لوگوںمیں کوئی نسبت ہی نہیں ہو گی اور جہاں تک خدا تعالیٰ کا تعلق ہے وہ باقی انسانوں کے مقابل پران سے الگ قسم کا سلوک کرے گا اور وہ انہیں اپنا مقرب بنا لے گا.اس آیت میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ مسلمانوں کو جو بادشاہتیں ملیں گی وہ بالکل الگ قسم کی ہوں گی وہ اس جہان کی بادشاہتوں کی طرح نہیں ہوں گی بلکہ مَرْفُوْعَۃٌ ہوں گی.ان کے تخت آسمان پر رکھے جائیں گے چنانچہ دیکھ لو مسلمان بادشاہ تو ہوئے مگر انہوں نے دنیوی طور پر بادشاہت سے کیا فائدہ اٹھایا؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تمام عالم اسلامی کے بادشاہ تھے مگر ان کو کیا ملتا تھا.پبلک کے روپیہ کے وہ محافظ تو تھے مگر خود اس روپیہ پر کوئی تصرف نہیں رکھتے تھے.بے شک حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بڑے تاجر تھے مگر چونکہ ان کو کثرت سے یہ عادت تھی کہ جونہی روپیہ آیا خدا تعالیٰ کی راہ میں دے دیااس لئے ایسا اتفاق ہوا کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور آپ خلیفہ ہوئے تو اس وقت آپ کے پاس نقد روپیہ نہیں تھا.خلافت کے دوسرے ہی دن آپ نے کپڑوں کی گٹھڑی اٹھائی اور اسے بیچنے کے لئے چل پڑے.حضرت عمر رضی اللہ عنہ رستہ میں ملے تو پوچھا کیا کرنے لگے ہیں؟ انہوں نے کہا آخر میں نے کچھ کھانا تو ہوا اگرمیں کپڑے نہیں بیچوںگا تو کھاؤں گا کہاں سے.حضرت عمرؓ نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا اگر آپ کپڑے بیچتے رہے تو خلافت کا کام کون کرے گا؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اگرمیں یہ کام نہیں کروں گا تو پھر گذارہ کس طرح ہو گا؟ حضر ت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ بیت المال سے وظیفہ لے لیں.حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میں یہ تو برداشت نہیں کرسکتا.بیت المال پر میرا کیا حق ہے.حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا جب قرآن کریم نے اجازت دی ہے کہ دینی کام کرنے والوں پر بھی بیت المال کا روپیہ صرف ہو سکتا ہے تو آپ کیوں نہیں لے سکتے.چنانچہ اس کے بعد بیت المال سے ان کا وظیفہ مقرر ہوگیا مگر اس وقت کے لحاظ سے وہ وظیفہ صرف اتنا تھا جس سے روٹی کپڑے کی ضرورت پوری ہوسکے.(الطبقات الکبـرٰی زیر عنوان ذکر بیعۃ ابی بکر) پھر حضرت عمررضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے ان کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بالکل سادہ طور پر اپنی زندگی بسر کرتے تھے.خلفاء میں سے صرف حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس
Page 140
دولت تھی مگر آپ چونکہ بہت سخی تھے اس لئے جو کچھ پاس ہوتا بالعموم تقسیم کر دیا کرتے تھے.لوگ ان پر اعتراض بھی کرتے کہ آپ نے فلاں کو مال دیا ہے.فلاں کو مال دیا ہے آپ جواب دیتے کہ تم کو اس سے کیا.میرا اپنا روپیہ ہے میں جہاں چاہوں خرچ کروں تم اس میں دخل دینے والے کون ہو.تو کوئی فائدہ بھی خلفاء نے بیت المال سے نہیں اٹھایا بلکہ تمام کا تمام روپیہ انہوں نے لوگوں کے فائدہ کے لئے اپنی نگرانی میں صرف کیا.غرض مسلمانوں کے تخت دوسروں کی نسبت بلند تھے.دنیا کے بادشاہ قومی خزانہ کو اپنا خزانہ سمجھتے ہیں اور وہ اس پر پورا پورا تصرف رکھتے ہیں آج پبلک اور بادشاہتوں میں یہی جنگ جاری ہے کہ لوگ کہتے ہیں تم روپیہ رعایا کے لئے خرچ کرو اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا روپیہ ہے ہم جس طرح چاہیں گے خرچ کریں گے.پس اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اسلامی حکومت کا نقشہ کھینچا ہے اور بتایا ہے کہ ان کے تخت مَرْفُوْعَۃٌ ہوں گے وہ لوگوں کے فائدہ کے لئے حکومت کریں گے گویا نام کے بادشاہ ہوں گے مگر حقیقتاً زمین کے بادشاہوں سے بہت بلند مقام پر ہوں گے.وہ خزانوں کو اپنے خزانے نہیں سمجھیں گے بلکہ ملک اور قوم کی مِلک تصور کریں گے.یہی اسلامی حکومت کے معنے ہیں کہ اس میں خزانہ کسی فرد کا نہیں ہوتا بلکہ قوم بحیثیت مجموعی اس خزانہ کی مالک ہوتی ہے میں نے دیکھا ہے بعض غیر احمدی جو ہماری جماعت کو بھی عام پیروں فقیروں کی جماعتوں کی طرح سمجھتے ہیں مجھے خط لکھتے ہیں کہ آپ بڑے مالدار ہیں آپ ہمیں اتنے ہزار یا اتنے لاکھ روپے دے دیں.میں انہیں جواب دیتا ہوں کہ میرے پاس جو مال آتا ہے وہ میرا نہیں سلسلہ کا ہوتا ہے میں اسے اپنی مرضی کے مطابق تقسیم کرنے کا حق نہیں رکھتا.غرض وہ لوگ یہ نہیں سمجھ سکتے کہ میں بھی کسی قانون کے ماتحت ہوں اور اس قانون کو توڑ کر بیت المال کے روپیہ کو خرچ کرنے کا حق نہیں رکھتا انہیں بہت سمجھایا جاتا ہے کہ مجھے خزانہ پر کلی اختیار نہیں بلکہ خدا تعالیٰ نے مجھے بھی بعض قوانین کے ماتحت رکھا ہے مگر ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی اور وہ یہی خیال کرتے ہیں کہ میں بخل کی وجہ سے ان کی مدد نہیں کرتا.یہ حالت بتاتی ہے کہ مسلمان اسلامی تعلیم سے آج کل کس قدر دور چلے گئے ہیں یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان امراء مغضوب ہیں جبکہ گذشتہ ایام میں مسلمان امراء اور بادشاہ نہ صرف اپنوں کے محبوب تھے بلکہ غیروں کے بھی محبوب تھے.کیونکہ وہ حکومت کے روپیہ کو ملک اور خصوصًا غرباء کی ترقی کے لئے خرچ کرتے تھے اور امراء بھی اپنے اموال کو ایک الٰہی امانت سمجھتے تھے اور اسے عیاشی پر نہیں بلکہ رفاہِ عام کے کاموں پر خرچ کرتے تھے.
Page 141
وَّ اَكْوَابٌ مَّوْضُوْعَةٌۙ۰۰۱۵ اور آب خورے دھرے ہوں گے.حلّ لُغات.اَکْوَابٌ.اَکْوَابٌ: آب خوروں کو کہتے ہیں (اقرب) اور مَوْضُوْعَۃٌ.مَوْضُوْعَۃٌ وَضَعَ سے ہے جس کے معنے رکھنے کے ہوتے ہیں لیکن اس میں اور حَطَّ میں فرق ہے حَطَّ کے معنے محض رکھنے کے ہوتے ہیں اور وَضَعَ کے معنے مناسب طور پر رکھنے کے ہوتے ہیں (اقرب).قرآن کریم میں ہے وَالْاَرْضَ وَضَعَھَا لِلْاَنَامِ (الرحـمٰن:۱۱) اس کے معنے یہ ہیں کہ زمین کو اس طرح بنایا کہ چارپایوں کو اس سے فائدہ پہنچے.اسی طرح فرمایا يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهٖ (النساء:۴۷) یعنی مناسب محل سے بدل کر دوسری جگہ رکھ دیتے ہیں.تفسیر.اَكْوَابٌ مَّوْضُوْعَةٌ کے تین معنے ہو سکتے ہیں.آب خورے مومنوں کے پاس رکھے جائیں گے چونکہ آب خورے کا کسی کے پاس رکھنا پینے کے لئے ہوتا ہے اس لئے ان معنوں سے یہ استنباط بھی ہو گا کہ وہ بھرے ہوئے ہوں گے.دوسرے اس کے یہ معنے ہیں کہ آب خورے ان کے پاس ہی دھرے ہوں گے.تیسرے معنے اس کے یہ ہیں کہ آب خورے چشموں کے پاس دھرے ہوں گے.اس آیت میں مسلمانوں کے قرب الٰہی اور ان کی سخاوت اور فیاضی کا ذکر کیا گیا ہے.آب خورے ان کے پاس رکھے جائیں گے، کا ایک اشارہ ان کے بھرے ہوئے ہونے کی طرف ہے پس اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اپنے انعامات کا جام لبا لب پلائے گا اور ہر وقت پلائے گا اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ مومن فضل و احسان کے جام بھر کر اپنے پاس رکھیں گے تا جو آئے اسے پلائیں.وہ علومِ آسمانی کے جام بھر بھر کر لوگوں کے سامنے پیش کریں گے اور کہیں گے لو جی یہ آب خورے پی لو.دوسرے معنے اس سے یہ نکلتے ہیں کہ آب خورے مومنوں کے پاس ہی رکھے ہوں گے یعنی علومِ آسمانی کا حصول ان کے لئے آسان کر دیا جائے گا ادنیٰ کوشش سے وہ روح کی پیاس بجھا سکیں گے تیسرے معنے اس کے یہ ہیں کہ آب خورے چشموں کے پاس دھرے ہوں گے یعنی دعوتِ عامہ ہو گی جو چاہے پئے.گویا.اوّل.ان کے سینوں کو علومِ آسمانی سے پُر کیا جائے گا.دوم.ان کا علم اور عرفان لوگوں کے لئے اس قدر وسیع ہو گا کہ کسی کو مانگنے کی ضرورت نہیں ہو گی.
Page 143
یہ ایک ایسی خوبی اور ایسا کمال ہے جس پر ہر قوم کو رشک کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو ان جیسا بنانے کی کوشش کرنی چاہیے.اسی خوبی کا اللہ تعالیٰ نے زیر تفسیر آیت میں ذکر کیا ہے اور بتایا ہے مسلمانوں میں یہ نہیں ہو گا کہ ایک شخص گاؤ تکیہ لگا کر بیٹھا ہوا ہو اور باقی لوگ اس کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہوں بلکہ تمام افراد کو عزت حاصل ہو گی، تمام افراد کو وجاہت حاصل ہو گی، تمام افراد کو عظمت حاصل ہو گی اور تکیے سب کے پیچھے ہوں گے کسی ایک فرد کے پیچھے بڑا سا تکیہ نہیں رکھا ہو گا.وَّ زَرَابِيُّ مَبْثُوْثَةٌؕ۰۰۱۷ اور فرش بچھے ہوئے ہوں گے.حلّ لُغات.زَرَابِیُّ.زَرَابِیُّ کے معنے نَمَارِقُ کے بھی ہوتے ہیں اور فرش کے بھی.زَرَابِیُّ کا واحد زِرْبِیٌّ بھی ہوتا ہے اور زَرْبِیَّۃٌ بھی (اقرب) مَبْثُوْثَۃٌ: بَثَّ سے اسم مفعول کا صیغہ ہے اور بَثَّ کے معنے ہیں کسی چیز کو پھیلایا (مفردات) اور مَبْثُوْثَۃٌ کے معنے ہوں گے پھیلائے ہوئے.تفسیر.زَرَابِیُّ مَبْثُوْثَۃٌ کے یہ معنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہر ملک میں عزت بخشے گا اور ہر قوم کے لوگ ان کو اپنی آنکھوں پر بٹھائیں گے.نَمَارِقُ مَصْفُوْفَۃٌ کے معنے تو یہ تھے کہ ان کے ہر فرد کو عزت کے مقام پر بٹھایا جائے گا یعنی ساری کی ساری قوم معزز ہو گی یہ نہیں ہو گا کہ کوئی ایک فرد معزز ہو اور باقی لوگ ذلیل ہوں بلکہ ہر ایک کے پیچھے تکیہ لگا ہوا ہو گا.اب زَرَابِیُّ مَبْثُوْثَۃٌ میں یہ بتاتا ہے کہ ان کی دنیا کے کونہ کونہ اور زمین کے گوشہ گوشہ میں عزت کی جائے گی زَرْبِیَّۃٌ کے معنے جیسا کہ بتائے جا چکے ہیں فرش کے ہوتے ہیں پس زَرَابِیُّ مَبْثُوْثَۃٌ کے یہ معنے ہوں گے کہ مسلمانوں کے لئے ہر جگہ فرش بچھے ہوئے ہوں گے دنیا کے ہر کونہ میں وہ معزز ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو ہر جگہ عزت دے گا اور ہر مقام پر ان کی وجاہت کا لوگوں پر اثر پڑے گا.یہی وجہ ہے کہ نَمَارِقُ کے لئے مَصْفُوْفَۃٌ کا لفظ استعمال کیا تھا اور زَرَابِیُّ کے لئے مَبْثُوْثَۃٌ کا لفظ استعمال کیا ہے.مَصْفُوْفَۃٌ کے معنے ہوتے ہیں صف میں رکھے ہوئے اور مَصْفُوْفَۃٌ کہنے سے مطلب یہ تھا کہ جب مسلمان مجالس میں حاضر ہوں گے سب کے سب عزت کے مقام پر بیٹھیں گے ان میں سے کوئی ذلیل نہ ہو گا.لیکن زَرَابِیُّ میں کسی خاص مجلس کا ذکر نہیں
Page 144
بلکہ عام ذکر ہے اور بتایا گیا ہے کہ وہ جہاں جائیں گے لوگ ان کے رستہ میں فرش بچھائیں گے.ان کا استقبال کر یں گے.ان سے عزت کے ساتھ پیش آئیں گے اور چاہیں گے کہ وہ ان کے گھروں میں رہیں اور اس طرح ان کے لئے برکت کا باعث بنیں.لوگ عموماً ظاہر پر مرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ استقبال وہی ہوتا ہے جب بڑی بڑی قالینیں بچھائی جائیں، شاندار دروازے بنائے جائیں، رنگ برنگ کی جھنڈیاں لگائی جائیں اور ظاہری لحاظ سے نمائش کی جائے حالانکہ اصل استقبال قالین بچھانا نہیں بلکہ آنکھوں کا فر شِ راہ کرنا ہے.ایک شاعر نے کہا ہے ع حضرتِ واعظ جو آئیں دیدہ و دل فرشِ راہ (دیوان غالب صفحہ ۳۰) پس لوگوں کے دیدہ و دل کا فرشِ راہ ہونا ہی اصل عزت کی علامت ہے اور اسی کی طرف زَرَابِیُّ مَبْثُوْثَۃٌ میں اشارہ کیا گیا ہے اس سے مراد ظاہری زَرَابِیُّ نہیں.ان ظاہری زَرَابِیُّ کی تو صحابہ کو پرواہ بھی نہیں تھی.جب ایران کے بادشاہ کے دربار میں صحابہؓ گئے تو وہ اپنے نیزوں کی اَنّی اس کے بڑے بڑے قیمتی قالینوں میں چبھوتے چلے جاتے تھے ایرانی دلوں میں کہتے تھے کہ یہ کیسے بد تہذیب ہیں کہ انہوں نے ہزاروں روپیہ کی قالینیں نیزے مار مار کر خراب کر دیں مگر انہیں اس کی کوئی پرواہ ہی نہیں تھی.جب بادشاہ کے سامنے پیش ہوئے تو اس نے صحابہؓ سے کہا کہ تم کیا جانو کہ سیاست کیا چیز ہوتی ہے بہتر یہ ہے کہ روپیہ لے لو اور واپس چلے جاؤ ناحق اپنی جانوں کو کیوں ضائع کرتے ہو.اس کا خیال تھا کہ عرب روپے لے کر خوش ہو جائیں گے اور لڑائی کا خیال ترک کر دیں گے.اس نے ان کی جو قیمت لگائی اس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ بیرونی اقوام اہلِ عرب کے متعلق کیسے ذلیل اندازے لگایا کرتی تھیں.معلوم ہوتا ہے عرب اس زمانہ میں ایسے ہی لالچی اور حریص ہوتے ہوں گے ورنہ ان کے متعلق وہ ایسا اندازہ کیوں لگاتا.اس نے حکم دیا کہ ہر سپاہی کو ایک ایک اشرفی اور ہر سردار کو دو دو اشرفی دی جائے.صحابہؓ نے اسے کہا اب تو دو صورتوں میں سے ایک ہی صورت ہے یا ہماری موت یا تمہاری موت.یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ اسلام جنگ شروع ہو جانے کے بعد کفر سے صلح کرے.یہ سن کر بادشاہ کو سخت غصہ آیا.اس نے مٹی کا ایک بورا بھروایا اور مسلمانوں کے سردار سے کہا کہ آگے آؤ.وہ آگے آئے تو اس نے وہ بورا ان کی پیٹھ پر لدوا دیا اور کہا اس مٹی کے بورے کے سوا اب تمہیں کچھ نہیں مل سکتا.ساتھی صحابہؓ کا خیال تھا کہ ان کا سردار مٹی کے اس بورے کو اٹھانے سے انکار کر دے گا اور کہے گا میں اس ہتک کو برداشت نہیں کر سکتا.مگر انہوں نے آگے بڑھ
Page 145
کر مٹی کا بورا اپنی پیٹھ پر رکھوا لیا جو ان کے ساتھیوں کو بہت برا لگا مگر انہوں نے اس بات کی کوئی پرواہ نہ کی بورا اٹھایا اور زور سے ایک نعرہ لگا کر اپنے ساتھیوں سے کہا آ جاؤ بادشاہ نے خود ایران کی زمین ہمارے حوالے کر دی ہے.مشرک تو ہوتا ہی وہمی ہے یہ سنتے ہی بادشاہ کا رنگ زرد ہو گیا اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور اس نے درباریوں سے کہا جلدی جاؤ اور ان کو پکڑ کے لے آؤ مگر وہ گھوڑوں پر سوار ہو کر اس وقت تک دور نکل چکے تھے اس لئے وہ ناکام واپس آئے.(البدایۃ و النـھایۃ: فصل فی غزوۃ القادسیۃ) دیکھو یہ کیسی لطیف اور باموقع بات اس صحابیؓ کو سوجھی باقی صحابہؓ کو اس کا خیال نہیں آیا وہ یہی سمجھتے رہے کہ ہمارے سردار نے اچھا نہیں کیا جو مٹی کا بورا اٹھا لیا مگر جب اس نے نعرہ لگا کر حقیقت ظاہر کی تب انہیں پتہ لگا کہ یہ کیسی لطیف بات تھی.پھر دیکھو صحابہؓ جس جگہ بھی گئے لوگوں نے ان کا عزت سے استقبال کیا.یوروشلم کا واقعہ ایک مشہور تاریخی واقعہ ہے پہلے مسلمانوں نے اسے فتح کر لیا مگر کچھ عرصہ کے بعد دشمن نے بڑے لشکروں سے اس پر حملہ کر دیا اور مسلمانوں کو یوروشلم چھوڑ کر پیچھے ہٹنا پڑا.جب مسلمان لشکر واپس آنے لگا تو یوروشلم کے عیسائی روتے تھے حالانکہ اس وقت مسلمانوں کا عیسائیوں سے مقابلہ تھا اور عیسائیوں کا اپنا ہم مذہب بادشاہ یوروشلم پر قابض ہو رہا تھا مگر اس کے باوجود وہ مسلمان لشکر کو شہر کے باہر تک چھوڑنے کے لئے آئے اور ساتھ ساتھ یہ کہتے جاتے تھے کہ خدا تم کو پھر ہمارے ملک میں واپس لائے(فتوح البلدان للبلاذری: امر حمص و یوم الیرموک).تو دیکھو ان کا اپنا ملک تھا.اپنی قوم مسلمانوں سے برسر جنگ تھی.مگر انہیں اپنے مذہب کی بادشاہت کے مقابلہ میں ایک غیر قوم کی حکومت اچھی لگتی تھی اور وہ دعائیں کرتے تھے کہ خدا مسلمانوں کو پھر ہمارے شہر میں واپس لائے.غرض بتایا کہ مسلمان جہاں جائیں گے لوگ اپنی آنکھیں فرشِ راہ کریں گے اور کہیں گے آئیے اور تشریف رکھیے.آخر وہ کون سی چیز تھی جس کی وجہ سے اسلام کو فتح حاصل ہوئی.اور مسلمان جہاں گئے پھیلتے چلے گئے اس کی وجہ یہی تھی کہ مسلمان منصف مزاج تھے اور وہ لوگوں کے حقوق کو غصب نہیں کرتے تھے.غصہ سے انسان تب لڑتا ہے جب وہ سمجھتا ہے کہ میرا نقصان ہو رہا ہے لیکن جب وہ سمجھتا ہو کہ ہمارے اپنے بادشاہ ظلم کرتے ہیں مسلمان آئیں تو انصاف کریں گے اس وقت وہ دل سے نہیں لڑ سکتا بلکہ عزت کے ساتھ پیش آتا ہے.پس فرماتا ہے مسلمانوں کی حالت یہ ہو گی کہ وہ جدھر جائیں گے لوگ اپنی آنکھیں ان کی راہ میں بچھائیں گے جس جگہ ٹھہریں گے لوگ تکیے لگائیں گے.ان کے قدموں میں قالینیں بچھائیں گے جیسے گورنروں یا حاکموں کے استقبال کے موقع پر ہوتا ہے اور کہیں گے کہ ہمارے ہاں ہی ٹھہریئے اور آگے نہ جائیے.
Page 146
اَفَلَا يَنْظُرُوْنَ اِلَى الْاِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْٙ۰۰۱۸ کیا وہ اونٹوں کونہیں دیکھتے کہ وہ کس طرح پیدا کئے گئے ہیں.وَ اِلَى السَّمَآءِ كَيْفَ رُفِعَتْٙ۰۰۱۹ اور آسمان کو (نہیں دیکھتے کہ) کس طرح اونچا کیا گیا ہے.حلّ لُغات.اِ بِلٌ.اِ بِلٌ: کے معنے اونٹوں کے ہوتے ہیں لیکن بعض علماء ادب نے اس کے معنے بادل کے بھی کئے ہیں.امام راغب نے اپنی کتاب مفردات میں لکھا ہے کہ اس کے معنے اگر بادل کے ہیں تو بھی استعارہ کے طور پر ہیں لغت میں یہ معنے نہیں ہیں(مفردات).گو بعض آئمہ نے حتی کہ کسائی تک نے کہا ہے کہ اس کے معنے بادل کے ہیں.جیسا کہ صاحبِ محیط کہتے ہیں وَرُوِیَتْ عَنْ اَبِیْ عَـمْرٍو وَاَبِیْ جَعْفَرٍ وَالْکِسَائِیِّ وَقَالُوْا اِنَّـھَا السَّحَابُ عَنْ قَوْمٍ مِنْ اَھْلِ اللُّغَۃِ(البحر المحیط زیر آیت ’’اَفَلَا يَنْظُرُوْنَ اِلَى الْاِبِلِ ‘‘).لیکن لغت کی کتب لکھنے والوں نے ان معنوں کو تسلیم نہیں کیا.وہ یہی کہتے ہیں کہ لغت کے لحاظ سے اس کے حقیقی معنے اونٹوں کے ہی ہیں.میں بھی پہلے اس آیت میں اِ بِل کے معنے اونٹوں کی بجائے بادل کے کیا کرتا تھا اور سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اگر اِ بِل کے معنے یہاں اونٹوں کے ہی کئے جائیں تو پھر اِ بِل اور سَـمَاء میں جوڑ کیا ہوا.اس وقت بادل کے معنے زیادہ قرین قیاس معلوم ہوتے تھے لیکن اب جو میں نے غور کیا تو یہی بات ٹھیک نکلی کہ اس آیت میں اِ بِل کے معنے اونٹوں کے ہی ہیں.پہلے میں اس آیت پر صرف اسی آیت کو سامنے رکھ کر غور کرتا رہا ہوں.لیکن اب جو میں نے ترتیب آیات کے لحاظ سے غور کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ اونٹوں کا سَـمَاء کے ساتھ تو جوڑ نظر آتا ہے مگر بادل کا کوئی جوڑ نہیں جیسا کہ مفردات والوں اور صاحب کشاف نے لکھا ہے یہ درست معلوم ہوتا ہے کہ اِ بِل کے معنے جن لوگوں نے بادل کے کئے ہیں فَعَلٰی تَشْبِیْہِ السَّحَابِ یعنی وہ اس وجہ سے کئے ہیں کہ اونٹ اس طرح اونچے نیچے چلتے ہیں جس طرح بادل چلتا ہے.پس چونکہ اِ بِل کو چلنے کے لحاظ سے بادلوں سے مشابہت ہوتی ہے اس لئے محاورہ میں اِ بِل کا لفظ بادل کے لئے استعمال کیا جانے لگا ورنہ اِ بِل کے اصل معنے بادل کے نہیں ہیں(مفردات).تفسیر.اَفَلَا يَنْظُرُوْنَ اِلَى الْاِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ.وَاِلَى السَّمَآءِ كَيْفَ رُفِعَتْ میں مضمون نیچے سے اوپر گیا ہے اور اگلی آیت یعنی وَ اِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ.وَ اِلَى الْاَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ میں مضمون اوپر سے نیچے آیا
Page 147
ہے.اس سے صاف پتہ لگتا ہے کہ یہاں دو الگ الگ مضمون بیان ہوئے ہیں.ایک مضمون میں نیچے سے اوپر کی طرف توجہ دلائی گئی ہے اور دوسرے مضمون میں اوپر سے نیچے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے.اگر ان آیات میں دو الگ الگ مضمون تسلیم نہ کئے جائیں تو پھر اِ بِل، سَـمَاء، جبال اور ارضمیں کوئی بھی ترتیب نظر نہیں آتی.ترتیب کے لحاظ سے مدارج دو ہی طرح بیان کئے جا سکتے ہیں یا نیچے سے اوپر کی طرف مضمون کو لے جایا جائے یا اوپر سے نیچے کی طرف.اب اس آیت میں پہلے اونٹوں کاذ کر ہے پھر سَـمَاء کا.یہاں تک تو ترتیب درست ہے یعنی نیچے سے اوپر کی طرف مضمون لے جایا گیا ہے مگر اس کے بعد پہاڑوں کا ذکر ہے جو نہ سَـمَاء سے اونچے ہیں نہ ان کے برابر.اور اس کے بعد زمین کا ذکر ہے جو پہاڑوں سے اونچی نہیں ہوتی.دوسری ترتیب یہ ہوتی ہے کہ اوپر سے نیچے کی طرف آیا جائے مگر اس لحاظ سے بھی بات نہیں بنتی کیونکہ اونٹ جو چھوٹی چیز ہے اس کا پہلے ذکر کر دیا گیا ہے اور سَـمَاء جو بلند چیز ہے اس کا بعد میں ذکر کیا گیا ہے گویا نہ یہ ترتیب بنتی ہے کہ اونٹ سب سے نیچا ہو.اس سے اونچا آسمان ہو.اس سے اونچا پہاڑ ہو اور اس سے اونچی زمین ہو اور نہ یہ ترتیب بنتی ہے کہ اونٹ سب سے اونچا ہو آسمان اس سے نیچا ہو.پہاڑ اس سے نیچے ہوں اور زمین ان سے نیچی ہو.کبھی کبھی ایک اور رنگ بھی ترتیب کے بیان میں استعمال کر لیا جاتا ہے اور وہ اس طرح کہ پہلے درمیانی چیز کا ذکر کر دیا جاتا ہے پھر ان اشیاء کا ذکر کر دیا جاتا ہے جو اس کے دائیں بائیں ہوں مگر یہاں اِ بِل کے بعد آسمان کا ذکر دیا گیا ہے.آسمان کے بعد پہاڑوں کا اور پہاڑوں کے بعد زمین کا.اگر چوٹی کی چیز کو پہلے بیان کر دیا جاتا اور اس کے بعد ایسی چیزوں کا نام لیا جاتا جو اس سے کم اونچی ہیں تو خیر کوئی بات بھی تھی مگر بظاہر اس جگہ کوئی اصل بھی مدنظر نہیں رکھا گیا.نہ نیچے سے اوپر مضمون گیا ہے نہ اوپر سے نیچے کو مضمون گیا ہے اور نہ درمیان کی کسی چیز کا پہلے ذکر کر کے اس سے تعلق رکھنے والی چیزوں کا بعد میں ذکر کیا گیا ہے.پس یا تو ان آیات کو بے ترتیب قرار دینا پڑے گا جو قرآن کریم کی شان کے خلاف ہے یا ان آیات کو دو الگ الگ مثالوں پر مشتمل قرار دینا ہو گا.جن میں سے ایک میں نیچے سے اوپر کی طرف مضمون لے جایا گیا ہے اور دوسری میں اوپر سے نیچے کی طرف ایک مثال کے ذریعہ اِ بِل اور سـماء کی آپس میں کوئی نسبت بتائی ہے اور دوسری ـمثال کے ذریعہ جبال اور ارض کی آپس میں کوئی نسبت بتائی ہے.اور میرے نزدیک ان آیات میں یہی آخری طریق استعمال ہوا ہے.اِ بِل کے معنے اس جگہ اونٹوں ہی کے ہیں لیکن سـماء کے معنے اس جگہ آسمان کے نہیں بلکہ بادل کے ہیں جیسا کہ وَالسَّمَآءِ ذَاتِ
Page 148
الرَّجْعِ (الطارق:۱۲) میں سـماء کے معنے بادل کے ہیں.اَفَلَا يَنْظُرُوْنَ اِلَى الْاِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ میں کفار مکہ کی مشابہت اِ بِل سے اہل مکہ کا طریق تھا کہ وہ ہمیشہ فخر ومباہات سے کام لیا کرتے تھے اور تکبّر میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اپنی شان اور وجاہت کا بار بار ذکر کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ ہم ایسی شان والے.ہم اتنا بلند مرتبہ رکھنے والے.ہم ایسے اور ہم ویسے مسلمان بھلا ہمارے مقابلہ میں جیت سکتے ہیں.اس کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم اپنی شانیں تو بیان کرتے ہو مگر تمہاری حالت بالکل اونٹوں کی سی ہے.اونٹ بے شک اونچا ہوتا ہے مگر جانتے ہو وہ ہمیشہ دوسرے کی سواری کے ہی کام آتا ہے بے شک اس کی کوہان اونچی ہوتی ہے، اس کا قد اونچا ہوتا ہے، اس کی ٹانگیں لمبی ہوتی ہیں، اس کا جسم بڑا ہوتا ہے مگر اس کے باوجود وہ ہمیشہ دوسروں کے نیچے رہتا ہے.اسی طرح تم خواہ اپنی کس قدر شانیں بیان کرتے رہو.تمہیں وہ قویٰ ہی نہیں دیئے گئے کہ تم حکومت کر سکو.تم ہمیشہ اسی قابل رہو گے کہ لوگ تمہاری گردنوں پر سوار ہو ں جیسے اونٹ بے شک اونچا ہوتا ہے مگر اونچا ہونے کے باوجود اسے نیچا ہونا پڑتا ہے اور ایک دوسرا شخص اس کی پیٹھ پر سوار ہو جاتا ہے.پس تم اپنی خوبیاں خواہ کتنی گنتے جاؤ تم اِ بِل کے مشابہ ہو اور اونٹ ہمیشہ سواری ہی دیتے ہیں.اوپر چھانے والے بادل ہوتے ہیں اونٹ نہیں ہوتے تم اونٹوں کی طرح ہمیشہ دوسروں کی سواری کے کام آتے رہے ہو کبھی دنیا پر تم نے حکومت نہیں کی.لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم کے صحابہؓ سـماء ہیں پس تمہاری اور ان کی آپس میں کوئی نسبت ہی نہیں.یہ بادلوں کی طرح دنیا پر چھا جانے والے ہیں اور تم خواہ کتنے اونچے ہو جاؤ بہرحال تمہاری پیٹھ پر دوسرے لوگ سوار ہوں گے چنانچہ عربوں کو دیکھ لو انہوں نے کئی صدیوں سے دنیا پر حکومت نہیں کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ سے ان کی تاریخ محفوظ ہے اور اس سے پتہ لگتا ہے کہ وہ ہمیشہ دوسروں کے محکوم چلے آتے تھے کسی قسم کا غلبہ ان کو حاصل نہیں ہوا تھا لیکن وہی قوم جو پچیس۲۵۰۰ سو سال سے بالکل ذلیل چلی آتی تھی جس کو ہر لحاظ سے ادنیٰ قرار دیا جاتا تھا.جسے دنیا میں کہیں غلبہ حاصل نہ تھا اور جس کے افراد کو حکومت کا کوئی شعور نہیں تھا جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آئی اور آپ کے دامن کو اس نے چھؤاتو وہ دیکھتے ہی دیکھتے کہیں سے کہیں جا پہنچی اورد نیا کی فاتح اور حکمران بن گئی اور بادلوں کی طرح دنیا پر چھا گئی.پس آیت میں کفار کو اونٹوں سے مشابہت دی ہے کہ باوجود اونچا ہونے کے سواری کے کام آتے ہیں اور مسلمانوں کو بادلوں سے مشابہت دی ہے کہ نظر نہ آنے والے ذرّوں سے بنتا ہے اور آخر بلند ہو کر دنیا پر چھا جاتا ہے اور اسے سیراب کر دیتا ہے.
Page 149
وَ اِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْٙ۰۰۲۰ اور پہاڑوں کو (نہیں دیکھتے) کہ کس طرح گاڑے ہوئے ہیں.وَ اِلَى الْاَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْٙ۰۰۲۱ اور زمین کو (نہیں دیکھتے) کہ کس طرح ہموار کی ہوئی ہے.تفسیر.اس آیت میں دوسری مثال بیان کی گئی ہے جس کا مضمون اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے فرماتا ہے تم پہاڑوں کو دیکھو کہ وہ کس طرح زمین میں گڑے ہوئے ہیں.دوسری جگہ پہاڑوں کا فائدہ اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے کہ وَ جَعَلْنَا فِي الْاَرْضِ رَوَاسِيَ اَنْ تَمِيْدَ بِهِمْ (الانبیاء:۳۲) ہم نے پہاڑ اس لئے بنائے ہیں کہ زمین ہل نہ جائے اور لوگ تباہ نہ ہو جائیں.زمین کی غیر ضروری حرکت کو پہاڑوں نے ہی روکا ہوا ہے ورنہ بنی نوع انسان کا زمین میں قیام بالکل ناممکن ہو جاتا.اللہ تعالیٰ گذشتہ مضمون کے تسلسل میں کفار کو توجہ دلاتا ہے کہ تم اپنے دلوںمیں خیال کرتے ہو کہ یہ کیونکر ہوسکتا ہے کہ مسلمان غالب آ جائیں.اور ہم مغلوب ہوجائیں.ہم طاقتور اور بڑی عزت اور شان رکھنے والے ہیں یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہم قوم اور ہمارے ہم مذہب ہم کو چھوڑ کر ان کے پیچھے دوڑنے لگ جائیں.مگر تمہارا یہ خیال بالکل بے بنیاد ہے.تم بے شک اچھے ہو گے مگر تمہاری اور مسلمانوں کی حالت میں جو کچھ فرق ہے وہ اس سے ظاہر ہے کہ مسلمانوں کو ہم نے اپنی مشیت کے ماتحت پہاڑ بنایا ہے اور تم کو زمین بنایا ہے.زمین پہاڑوں کے ذریعہ ہی قائم رہتی ہے اگر پہاڑ نہ ہوں تو زمین بھی اس حالت میں نہ رہے.پس بے شک تم میں خوبیاں ہیں اس سے ہم انکار نہیں کرتے.جس طرح زمین میں بھی خوبیاں پائی جاتی ہیں اور کوئی شخص ان خوبیوں سے انکار نہیں کر سکتا مگر زمین یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ اسے پہاڑوں کی ضرور ت نہیںیا پہاڑوں کے بغیر بھی اس کی زندگی قائم رہ سکتی.زمین کی زندگی پہاڑوں کے بغیر قطعی طور پر ناممکن ہے.اسی طرح اب جبکہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ بنا دیا ہے تمہارا فائدہ اسی میں ہے کہ زمین کی طرح ان کے مقابلہ میں بچھ جاؤ.جس طرح زمین پہاڑ کے مقابلہ میں بچھ کر ہی فائدہ اٹھاتی ہے اس کے بغیر نہیں اسی طرح تمہارا فائدہ بھی اسی میں ہے کہ تم مسلمانوں کے مقابلہ میں کھڑے نہ ہو.مسلمانوں کی مثال پہاڑوں سے اور کفار کی مثال زمین سے اگر پہاڑ کی اونچائی کے لحاظ سے
Page 150
اس مثال کو مسلمانوں پر چسپاں کیا جائے تو پھر معنے یہ ہوں گے کہ مسلمانوں کی مثال پہاڑوں کی طرح ہے اور تمہاری مثال زمین کی طرح.ان مسلمانوں کے ذریعہ ہی اب دنیا سے فتنہ و فساد دور ہوں گے.بے شک زمین سرسبز و شاداب ہوتی ہے اور کئی قسم کی روئیدگیاں اس میں پیدا ہوتی ہیں مگر انہی پہاڑوں کے ذریعہ.کیونکہ وہی بادلوں کے برسنے کا ذریعہ بنتے ہیں اور وہی دریاؤں کا منبع ہیں پس اب تمہاری ترقی مسلمانوں کے ساتھ وابستہ ہے ان سے جدا ہو کر تم سکھ نہیں پا سکتے.فَذَكِّرْ١ؕ۫ اِنَّمَاۤ اَنْتَ مُذَكِّرٌؕ۰۰۲۲ پس نصیحت کر کہ تُو تو صرف نصیحت کرنے والا ہے.تفسیر.فرماتا ہے جبکہ تمام ترقیات اور فوائد مسلمانوں کے ساتھ وابستہ ہیں.محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہو کر ہی ہر قسم کی برکات کا حصول انسان کے لئے ممکن ہے خدا نے ان کو بادلوں کی طرح دنیا پر چھا جانے والے اور پہاڑوں کی طرح زمین کے فتنہ و فساد کو دور کرنے والے اور ہر قسم کے فوائد لوگوں کو پہنچانے والے بنایا ہے تو پھر اے مسلمانو! تمہارا بھی فرض ہے کہ تم مخالفینِ اسلام کو سمجھاؤ اور انہیں کہو کہ وہ بھی اسلام کو قبول کر لیں اونٹ بن کر انہوں نے کیا لینا ہے.اگر بننا ہے تو بادل بنیں اور پہاڑوں کی طرح دنیا کو فائد ہ پہنچائیں اور زمین کی طرح دوسری اقوام کے پاؤں تلے روندے نہ جائیں.لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَۜيْطِرٍۙ۰۰۲۲ تو ان (لوگوں) پر داروغہ (کے طور پر) مقرر نہیں ہے.اِلَّا مَنْ تَوَلّٰى وَ كَفَرَۙ۰۰۲۳ مگر جس نے پیٹھ پھیر لی اور کفر کا مرتکب ہوا.حلّ لُغات.اَلْمُصَیْطِر: سین سے بھی لکھا جاتا ہے اور صاد سے بھی ہے.اور اَلْمُصَیْطِر بھی ہے اور اَلْمُتَصَیْطِر بھی استعمال ہوتا ہے اور اس کے معنے ہیں اَلرَّقِیْبُ اَلْـحَافِظُ وَالْمُسَلَّطُ عَلَی الشَّیْءِ لِیُشْـرِفَ عَلَیْہِ
Page 151
وَیَتَعَھَّدَ اَحْوَالَہٗ وَیَکْتُبَ عَـمَلَہٗ وہ شخص جو کسی کی پوری نگرانی کرے اس کے حالات کو دیکھتا رہے اور اس کے اعما ل کو لکھتا رہے (اقرب) پس لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَۜيْطِرٍ کے یہ معنے ہوئے کہ خدا نے تمہیں ان پر مُصَیْطِر نہیں بنایا اِلَّا مَنْ تَوَلّٰى وَ كَفَرَ سوائے اس کے جو تولّی اختیار کرتا اور کفر میں مبتلا رہتا ہے.یہاں اِلَّا استثناء منقطع کے معنے دیتا ہے متصل کے نہیں.یعنی تو کسی کا مصیطر نہیں ان کا بھی نہیں جو تَوَلّٰى اور کفر اختیار کریں مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو تَوَلّٰى کریں گے اور باوجود سمجھانے کے کفر میں مبتلا رہیں گے ان سے بھی تیرا واسطہ نہیں ہے.جن کے دلوں میں سعادت ہے انہی لوگوں نے تجھے ماننا ہے مگر نہ تجھے ماننے والوں پر مصیطر بنایا گیا ہے اور نہ انکار کرنے والوں پر اور تَوَلّٰى اور کفر اختیار کرنے والوں پر مصیطر بنایا گیا ہے تیرا ان سے کوئی واسطہ نہیں وہ اگر نہیں مانتے تو نہ مانیں ان کا معاملہ خدا کے ساتھ ہے.تفسیر.رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم کا مصیطر نہ ہونا دونوں لحاظ سے ہے مومنوں کے لحاظ سے بھی اور کافروں کے لحاظ سے بھی.یعنی آپ نہ مومنوں کے لئے مُصَیْطِر ہیں اور نہ کفار کے لئے مُصَیْطِر ہیں.کفار کو اگر جبراً مذہب میں شامل بھی کیا جائے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا.وہ ظاہر میں تو مذہب قبول کر لیں گے لیکن دل میں منافق رہیں گے اس لئے اللہ تعالیٰ نے لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَۜيْطِرٍ کہہ کر غیر مذاہب والوں کو جبراً اسلام میں شامل کرنے کی ممانعت فرما دی ہے اور بتایا ہے کہ ہم نے تمہیں ان کا داروغہ مقرر نہیں کیا.اگر تم جبر سے کام لو گے تو اس سے نہ مومن کو فائدہ ہو گا نہ کافر کو.کافر کو تو اس لحاظ سے فائدہ نہیں ہو گا کہ اگر وہ تلوار کے ڈر سے مسلمان ہو بھی جائے تو بہرحال وہ منافق مسلمان ہو گا اور منافق کافر سے بد تر ہوتا ہے.مومنوں کو اس لئے فائدہ نہ ہو گا کہ منافق ان کی طاقت کو کمزور کرنے والے ہوں گے بڑھانے والے نہیں.مومنوں پر مُصَیْطَر اس لئے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا ایسے ہی اعمال کے نتیجہ میں انسان کو حاصل ہو سکتی ہے جو دلی شوق اور رغبت سے کئے جائیں.جس شخص کے دل میں ذاتی طور پر خدا تعالیٰ کی محبت کا کوئی جوش نہیں، اس کے احکام پر عمل کرنے کا ولولہ اس کے سینہ میں نہیں پایا جاتا وہ معرفت اور اخلاص کی راہوں سے بیگانہ ہے.وہ اگر جبر کے ماتحت کوئی نیک کام کرے گا بھی تو اس کی روح کو پاکیزگی حاصل نہیں ہو گی اور خدا تعالیٰ کے حضور اس کے وہ اعمال قبولیت کی نگاہ سے نہیں دیکھیں جائیں گے اس لئے فرمایا کہ تمہیں لوگوں کا مصیطر بنا کر نہیں بھیجا گیا.جو شخص کفر کرے اور باوجود سمجھانے کے اپنے بداعمال سے باز نہ آئے اسے ہمارے سپرد کر دو تمہارے جبر سے کوئی فائدہ نہیں ہو گا.اور جو مسلمان ہے اسے شوق اور رغبت کے ذریعہ سے نیکی میں بڑھاؤ تا کہ اسے ایمان کا نفع حاصل ہو.
Page 152
یہاں بھی دیکھ لو اسلام اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلبہ کی کیسے کھلے لفظوں میں پیشگوئی کی گئی ہے.مکی زندگی میں جبکہ ابھی اسلام کا ابتدا تھا اور کسی کے وہم وگمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ اسلام بہت بڑی طاقت حاصل کر لے گا یہاں تک کہ کفار کی گردنیں مسلمانوں کے قبضہ میں ہوں گی اور وہ اختیار رکھتے ہوں گے کہ ان سے جو سلوک چاہیں کریں.اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَۜيْطِرٍ یہ صاف بات ہے کہ مکہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم کو کوئی ایسی طاقت حاصل نہیں تھی کہ آپ کو یہ کہا جاتا کہ تجھے ہم نے مصیطر بنا کر نہیں بھیجا.یہ آئندہ کے متعلق پیشگوئی کی گئی تھی اور اسلام کے غلبہ کی خبر دی گئی تھی ورنہ وہ لوگ جن کو مکہ میں کھلے بندوں نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہیں تھی ان کو یہ کہنا کہ تمہیں زبردستی کسی کو مسلمان بنانے کی اجازت نہیں ایک مضحکہ خیز بات ہو جاتی ہے.یہ فقرہ صاف بتا رہا تھا کہ وہ دن آنے والا ہے جب کہ مسلمانوں کو اتنی طاقت حاصل ہو جائے گی کہ وہ اگر چاہیں تو زبردستی لوگوں کو مسلمان بنا سکیں گے مگر پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے بطور نصیحت فرما دیا کہ تم ایسا نہ کرنا.لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَۜيْطِرٍ میں غلبہ اسلام کی پیشگوئی غرض لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَۜيْطِرٍ اِلَّا مَنْ تَوَلّٰى وَكَفَرَ میں غلبہ اسلام کی پیشگوئی پائی جاتی ہے.اور یہ بات ایسی ہے کہ عیسائی مصنّفین کو بھی کھٹکی ہے چنانچہ ویری اس آیت کے ماتحت لکھتا ہے آپؐکے دل میں شروع سے ہی حکومت کے خیالات اٹھ رہے تھے (1.Wherry,s Commentary On Quran vol:4 P:240 2.Wherry,s Commentary On Quran vol:1 P:333)چنانچہ ابتدائی زمانہ میں ہی اس قسم کی آیات مکہ والوں کو سنانا بتا رہا ہے کہ انہوں نے شروع سے ہی حکومت کا نقشہ اپنے ذہن میں جمایا ہوا تھا اور ویسے ہی خیالات دل میں پیدا ہوتے رہتے تھے مگر سوال یہ ہے کہ حکومت کے خیالات آخر کسی وجہ سے پیدا ہوا کرتے ہیں بغیر کسی وجہ کے پیدا نہیں ہو سکتے.وہ شخص جو ماریں کھا رہا ہو، جو لوگوں کے ظلم وستم کا نشانہ بنا ہوا ہو، جو اتنی طاقت بھی نہ رکھتا ہو کہ باہر نکل کر خدا تعالیٰ کی عبادت کر سکے اس کے دل میں حکومت کے خیالات پیدا ہی کس طرح ہو سکتے ہیں اور پھر خود ساختہ خیالات پورے کس طرح ہو گئے.درحقیقت یہ ایک پیشگوئی تھی اور اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ گو اس وقت تمہاری کوئی حیثیت نہیں مگر ایک زمانہ میں تم کو ایسا غلبہ حاصل ہونے و الا ہے کہ تم جو چاہو گے کر سکو گے مگر دیکھنا جب تمہیں غلبہ میسر آئے اس وقت ان لوگوں پر جبر نہ کرنا بلکہ ان کو اپنے حال پر چھوڑ دینا جو شخص ایمان لے آئے اسے اپنے اندر شامل کر لینا اور جو تَوَلّٰى اور کفر کرے اس کی پرواہ نہ کرنا.
Page 153
فَيُعَذِّبُهُ اللّٰهُ الْعَذَابَ الْاَكْبَرَؕ۰۰۲۴ اس کے نتیجہ میں اللہ اسے سب سے بڑا عذاب دے گا.تفسیر.تولّی اور کفر کرنے والوں کو بہت بڑا عذاب دیئے جانے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک بڑی ہدایت کا انکار کیا.سزا ہمیشہ جرم کے مطابق دی جاتی ہے معمول قصور ہو تو معمولی سزا دی جاتی ہے اور زیادہ قصور ہو تو زیادہ سزا دی جاتی ہے.ان کا جرم چونکہ معمولی نہیں ہو گا اس لئے انہیں سزا بھی غیر معمولی دی جائے گی کیونکہ انہوں نے اس رسول کا انکار کیا جو تمام رسولوں سے بڑا تھا اور جس کی شریعت تمام شریعتوں سے بڑی تھی.اِنَّ اِلَيْنَاۤ اِيَابَهُمْۙ۰۰۲۶ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْؒ۰۰۲۷ یقیناً انہیں ہماری ہی طرف لوٹنا ہے پھر ان سے حساب لینا بھی یقیناً ہمارا ہی کام ہے.حلّ لُغات.اِیَابٌ.اِیَابٌ: اٰبَ کا مصدر ہے اور اٰبَ کے معنے ہیں.لوٹا (اقرب) پس اِیَابٌ کے معنے ہوں گے.لوٹنا.تفسیر.اس آیت سے اس مضمون کو ختم کیا گیا ہے جو سورۃ الاعلیٰ سے شروع کیا گیا تھا اور بتایا گیا ہے کہ مومن و کافر اپنے اپنے کام پورے کر کے مومن تسبیح کو بلند کر کے اور کافر کفر کی اشاعت کر کے آخر اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور دنیوی نتائج دیکھ کر اخروی نتائج دیکھنے کے لئے خدا تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہوں گے.سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ دونوں کے متعلق یہ امر بتایا جا چکا ہے کہ ان کا آپس میںگہرا ربط ہے اس کا ایک ثبوت اس امر سے بھی ملتا ہے کہ احادیث میں آتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى پڑھتے تو فرماتے سُـبْحَانَ رَبِّیَ الْاَعْلٰی اور جب سورۃ الغاشیہ کی تلاوت کرتے کرتے اِنَّ اِلَيْنَاۤ اِيَابَهُمْ ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ پر پہنچتے تو فرماتے اَللّٰھُمَّ حَاسِبْنِیْ حِسَابًا یَّسِیْـرًا.(مـسـنـد احـمـد بـن حـنـبـل و مسند ابن عباسؓ و مسند عائشۃ ؓ ) ایک سورۃ کے شروع میں ایک فقرہ کا دہرانا اور دوسری سورۃ کے آخر میں دوسرے فقرے کا دہرانا صاف طور پر بتا رہا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم کے نزدیک یہ دونوں سورتیں
Page 155
سُوْرَۃُ الفَجْرِمَکِّیَّۃٌ سورۂ فجر.یہ سورۃ مکی ہے وَ ھِیَ ثَلٰثُوْنَ اٰیَۃً دُوْنَ الْبَسْمَـلَۃِ وَ فِیْـھَا رُکُوْعٌ وَّاحِدٌ اور بسم اللہ کے علاوہ اس کی تیس آیتیں ہیں اور ایک رکوع ہے سورۃ الفجر مکی ہے یہ سورۃ مکی ہے فتح البیان والے لکھتے ہیں ھِیَ مَکِّیَّۃٌ بِلَاخِلَافٍ فِی قَوْلِ الْـجُمْھُوْرِ.(تفسیر فتح البیان سورۃ الفجر ابتدائیۃ) جمہور علماء کے نزدیک اس کے مکی ہونے میں کوئی اختلاف نہیں.ابن عباسؓ، ابن زبیرؓ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی یہی مروی ہے.رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم سورۃ الاعلیٰ، سورۃ الغاشیہ، سورۃ الفجر اور اسی قسم کی بعض اور سورتوں کو عام طور پر فرض نمازوں میں پڑھنا زیادہ پسند فرمایا کرتے تھے.نسائی نے جابرؓ سے روایت کی ہے کہ حضرت معاذ بن جبلؓ ایک دفعہ نماز پڑھا رہے تھے کہ ایک آدمی ان کے ساتھ پیچھے سے آ کر شامل ہوا.حضرت معاذؓ نے نماز لمبی شروع کر دی بعض روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے سورۂ آل عمران یا سورۂ نساء کی تلاوت شروع کر دی تھی.جب نماز لمبی ہو گئی تو اس نے نماز توڑ کر ایک دوسرے کونہ میں جا کر علیحدہ نماز شروع کر دی اور فارغ ہو کر چلا گیا.نماز کے بعد کسی شخص نے حضرت معاذؓ سے اس واقعہ کا ذکر کیا اور کہا کہ آپ نماز پڑھا رہے تھے کہ ایک شخص آیا اور اس نے آپ کے ساتھ نماز شروع کی مگر جب آپ نے نماز میں دیر لگا دی تو وہ نماز توڑ کر علیحدہ ہو گیا اور ایک کونے میں نماز پڑھ کر چلا گیا.حضرت معاذؓ نے کہا وہ منافق ہو گا پھر انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس واقعہ کا ذکر کر دیا اور کہا یا رسول اللہ! میں نماز پڑھا رہا تھا کہ پیچھے فلاں شخص آ کر شامل ہوا مگر جب نماز لمبی ہوگئی تو وہ نماز توڑ کر الگ ہو گیا اور علیحدہ نماز پڑھ کر چلا گیا.جب اس شخص کو معلوم ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم کے پاس میری شکایت کی گئی ہے تو وہ آپؐکی خد مت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا یا رسول اللہ میں آیا تو یہ نماز پڑھا رہے تھے میں ان کے ساتھ نماز میں شامل ہو گیا مگر انہوں نے نماز لمبی کر دی.آخر ہم کام کرنے والے آدمی ہیں میری اونٹنی بغیر چارہ کے کھڑی تھی میں نے نماز توڑ کر مسجد کے ایک کونے میں اپنی نماز ختم کر لی اور پھر گھر جا کر
Page 156
اپنی اونٹنی کو چارہ ڈالا.رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم یہ سن کر حضرت معاذؓ پر ناراض ہوئے اور ان سے فرمایا معاذ! کیا تم لوگوں کو فتنہ میں ڈالتے ہو تمہیں سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى اور وَ الشَّمْسِ وَ ضُحٰىهَا اور وَالْفَجْرِ اور وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى کے پڑھنے میں کیا تکلیف ہوتی تھی تم نے یہ سورتیں کیوں نہ پڑھیں اور لمبی سورتیں کیوں شروع کر دیں.اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سورتوں کو اوسط سورتوں میں قرار دیا ہے.خاص اوقات میں انسان بے شک لمبی سورتیں پڑھ لے یا تکلیف اور بیماری کی صورت میں چھوٹی سورتیں پڑھ لے.لیکن اوسط سورتیں یہی ہیں جن کو عام طور پر بالجہر نمازوں میں پڑھنا چاہیے.سورۃ الفجر کا زمانہ نزول اس سورۃ کی نسبت یوروپین مفسرین کا خیال ہے کہ یہ ابتدائی سالوں کی ہے اور میرے نزدیک یہی درست ہے.نولڈکے جرمن محقق اسے سورۃ الغاشیہ کے معاً بعد کی قرار دیتا ہے (A Comprehensive Commentary On Quran by Wherry Vol:4 Page:242) اور غاشیہ کی نسبت یوروپین مفسرین کی رائے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ اسے تیسرے اور چوتھے سال کے ملتے ہوئے حصوں کی قرار دیتے ہیں یعنی ان کے نزدیک یہ سورۃ یا تیسرے سال کے آخری نصف میں نازل ہوئی ہے یا چوتھے سال کے پہلے نصف میں نازل ہوئی ہے یا چوتھے سال کے پہلے نصف میں نازل ہوئی ہے اور یہ رائے درست معلوم ہوتی ہے کیونکہ ان سورتوں میں مخالفت کی ابتدا کی طرف اشارہ کیا گیا ہے منظّم اور تفصیلی مخالفت کا اس میں ذکر نہیں بلکہ یہ بتایا گیا ہے کہ مخالفت ہونے والی ہے اور یہ وہی زمانہ تھا جو تیسرے سال کا آخری یا چوتھے سال کا شروع تھا.وہ تفصیلی مخالفت جس کا ذکر ان سورتوں میں ہے جو مخالفت کے بعد اتریں ان کا ذکر یہاں نہیں.دوسری بات یہ ہے کہ یہاں کفار کے وہ عیوب گنائے گئے ہیں جو اخلاقی، شرعی اور دینی ہوتے ہیں مثلاً یتامیٰ کی خبر گیری کیوں نہیں کرتے، مساکین کو کھانا کیوں نہیں کھلاتے.اس قسم کے عیوب ہر زمانہ میں ہی گنائے جاتے ہیں لیکن جب نبوت کی کھلی مخالفت شروع ہو اس وقت زیادہ زور انکارِ نبوت کے جرم پر دیا جاتا ہے اور اس جرم کو باقی تمام جرائم کی اساس اور بنیاد سمجھا جاتا ہے اس وقت تفصیلی جرائم کی طرف توجہ نہیں کی جاتی.جب تک لوگ نبی کی مخالفت نہیں کرتے اس وقت تک ان کے اور نقائص پر زور دیا جاتا ہے مثلاً انہیں کہا جاتا ہے کہ تم یتامیٰ سے حسنِ سلوک نہیں کرتے، بیواؤں کی خبر گیری نہیں کرتے، مساکین کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ پیش نہیں آتے، اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے لیکن جب وہ مامور کی مخالفت کرتے ہیں تو سارا زور اس بات پر صرف کر دیا جاتا ہے کہ سب سے بڑا عیب تم میں یہ ہے کہ تم ایک نبی کے منکر ہو.اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان بالرسالت تمام اعمال صالحہ
Page 157
کے لئے ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے، جب لوگ نبی کو ماننے لگ جاتے ہیں تو ان کی اخلاقی اصلاح آپ ہی آپ ہو جاتی ہے.حقیقت یہی ہے کہ کفار جب نبی کی مخالفت اس کے دعویٰ کے متعلق زور شور سے شروع کر دیتے ہیں تو ان کا یہ جرم باقی تمام جرائم سے بڑھ جاتا ہے کیونکہ سب نیکیاں نبیوں سے شروع ہوتی ہیں نبی کے انکار کا جرم سب نیکیوں کے انکار کا موجب ہوتا ہے اس لئے اس وقت زیادہ زور اسی انکارِ نبوت کے جرم پر دیا جاتا ہے کیونکہ اس کی اصلاح باقی سب باتوں میں اصلاح کروا سکتی ہے.مگر اس سے پہلے کے عرصہ میں جب دعویٰ کا ابتداء ہوتا ہے تفصیلی نقائص کی طرف زیادہ توجہ دی جاتی ہے.یہ نہیں کہ بعد میں تفصیلات کا ذکر نہیں ہوتا.ذکر تو ہوتا ہے لیکن ان پر زور کم کر دیا جاتا ہے کیونکہ ایک ہی اصلاح کے ساتھ سب امور کی اصلاح وابستہ ہونے سے تفصیلات کی اہمیت کم ہو جاتی ہے.ہم نے دیکھا ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام پر لوگ ہمیشہ یہ اعتراض کیا کرتے تھے کہ آپ ان باتوں پر تو زیادہ زور دیتے ہیں کہ مجھے یہ الہام ہوا ہے وہ الہام ہوا ہے مگر اور امور کی طرف توجہ نہیں کرتے آپ اس کے جواب میں فرمایا کرتے تھے کہ سارے نقائص اور عیوب خدا تعالیٰ سے بُعد کے نتیجہ میں پیدا ہوتے ہیں.اگر لوگوں کو خدا تعالیٰ کی ذات کے متعلق کامل یقین پیدا ہو جائے تو ان سے گناہ سرزد نہ ہوں.میں لوگوں کے سامنے خدا تعالیٰ کے تازہ بتازہ الہامات اور اس کے نشانات ومعجزات کو بار بار اس لئے پیش کرتا ہوں کہ ان کے دلوں میں خدا تعالیٰ کے متعلق یقین پیدا ہو جائے جس دن ان کے دلوں میں سچا یقین پیدا ہوا اور انہوں نے مجھے مان لیا یہ عیوب آپ ہی آپ دور ہو جائیں گے.غرض جب تک لوگ نبوت کی کھلی مخالفت نہیں کرتے جزئیات کی طرف زیادہ توجہ دلائی جاتی ہے اور انہیں کہا جاتا ہے کہ تم میں یہ بھی نقص ہے وہ بھی نقص ہے.مگر جب وہ کھلے بندوں نبی کی مخالفت کے لئے کھڑے ہو جاتے ہیں جب وہ کہتے ہیں ہم اس نبی کو اور اس نبی کے ماننے والوں کو کچل کر رکھ دیں گے اس وقت ان کے اس نقص کو جو بنیادی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے کلام پر ایمان میں کمی، اسے سامنے رکھ کر اس کی اصلاح پر زور دیا جاتا ہے اور اسی میں باقی تمام جزئیات کی اصلاح آ جاتی ہے.اس سورۃمیں بھی کفار کے تفصیلی گناہوں پر زیادہ زور دیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ وہ یتامیٰ کی طرف توجہ نہیں کرتے، مساکین کو کھانا نہیں کھلاتے، ان کے دلوں میں یہ حرص پائی جاتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ مال اپنے پاس جمع کر لیں.یہ نقائص ان کے ایمان کی کمزوری پر دلالت کرتے ہیں اس کی اصلاح ہونی چاہیے.ان
Page 158
تفصیلات سے صاف پتہ لگتا ہے کہ یہ سورۃ اس وقت کی ہے جب ابھی قومی طور پر مخالفت شروع نہیں ہوئی تھی اسی لئے اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار پر اتنا زور نہیں جتنا اعمال کی جزئیات پر زور ہے بالخصوص ایسے گناہوں پر جو اسلام کے مقابلہ کے وقت اسلام کی شوکت اور ان کی تباہی کا موجب ہونے والے تھے پس یہ سورۃ یقیناً ابتدائی ایام کی ہے اور چونکہ اس میں اشارۃً یہ ذکر آتا ہے کہ اب منظم مخالفت ہونے والی ہے اس لئے یہ سورۃ تیسرے سال کے آخر یا چوتھے سال کے بالکل ابتدائی حصہ کی ہے.ترتیبِ سورۃ ابوحیان کہتے ہیں کہ سورۃ غاشیہ میں وُجُوْهٌ يَّوْمَىِٕذٍ خَاشِعَةٌ عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ میں کچھ لوگوں کے متعلق ذکر کیا گیا تھا کہ وہ ذلیل اور رسوا ہوں گے.اب اس سورۃ میں اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو یتامیٰ کی خبر گیری نہیں کرتے، مساکین کی طرف توجہ نہیں کرتے اور حریص اور لالچی ہیں.اسی طرح وُجُوْہٌ يَّوْمَىِٕذٍ نَّاعِمَۃٌ میں ایک اور گروہ کا ذکر کیا گیا تھا جو اللہ تعالیٰ کے حضور عزت پانے والا تھا اس سورۃ میں اس کا ذکر يٰۤاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَىِٕنَّةُ ارْجِعِيْۤ اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً کے ذریعہ کیا گیا ہے.(البحر المحیط ابتداء سورۃ الفجر) اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ دونوں ذکر اس سورۃ میں موجود ہیں اور اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ ان دونوں امور میں سے ایک کا تعلق وُجُوْهٌ يَّوْمَىِٕذٍ خَاشِعَةٌ سے ہے اور دوسرے کا تعلق وُجُوْہٌ يَّوْمَىِٕذٍ نَّاعِمَۃٌ سے ہے مگر یہ صرف قریبی تعلق ہے.یعنی پہلی سورۃ کے بعض مضامین سے اس سورۃ کے بعض مضامین کا باہمی رابطہ ملتا ہوا معلوم ہوتا ہے مگر مضمون کا وہ تسلسل جو ایک زنجیر کی طرح دونوں میں پایا جانا چاہیے وہ انہوں نے نہیں بتایا.جہاں تک قریبی تعلق کا سوال ہے ابوحیان نے خوب کام کیا ہے اور وہ اکثر تعلقاتِ سُوَر کے بارہ میں بڑی نگاہ رکھنے والے انسان ہیں بلکہ اس امر میں تمام پرانے مفسروں سے منفرد ہیں اور ممتاز بھی.مگر اس قریبی تعلق کے علاوہ قرآن کریم کی سورتوں اور آیتوں میں ایک مسلسل زنجیر بھی معلوم ہوتی ہے جو دور دور تک مضامین کی لڑی پروتی چلی جاتی ہے اور بالآخر سارے قرآن کریم کو ایک ہی ہار بنا کر رکھ دیتی ہے.رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم نے وحی کی مثال صَلْصَلَۃُ الْـجَرْسِ سے دی ہے(صحیح البخاری کتاب بدء الوحی باب کیف کان بدء الوحی) جس میں اس طرف اشارہ پایا جاتا ہے کہ جس طرح گھنٹی کی جھنکار میں ایک تسلسل ہوتا ہے اسی طرح وحی ایک مربوط اور مسلسل الٰہی کلام ہوتا ہے اور چونکہ قرآن کریم وہ کلام ہے جو تمام الٰہی کلاموں میں سے افضل ہے اس لئے وحی الٰہی کی صَلْصَلَۃُ الْـجَرْسِ سے تشبیہ دے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
Page 159
نے اس امر کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ قرآن کریم کو بے ترتیب نہ سمجھنا یہ خدا تعالیٰ کی وحی ہے اور اس کا ہر حصہ دوسرے حصہ سے پرویا ہوا ہے.اس وسیع اور لمبے سلسلہ کی طرف علامہ ابو حیان کی نظر نہیں گئی مگر پھر بھی ان کی خدمت ترتیبِ قرآن کریم کے بارہ میں بہت قابل قدر اور قابلِ ستائش ہے جَزَاہُ اللہُ اَحْسَنَ الْـجَزَاء.جیسا کہ میں نے اوپر بتایا ہے سورتوں کے باہمی تعلقات دو قسم کے ہوا کرتے ہیں.ایک قریبی تعلق جس میں یہ مدنظر رکھا جاتا ہے کہ ایک سورۃ کی آخری آیت کا مضمون دوسری سورۃ کی پہلی آیت سے ملا دیا جائے.اس کی ایسی ہی مثال ہے جیسے سورۂ فاتحہ میں اِھْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ کہہ کر ہدایت کے متعلق دعا مانگی گئی تھی اس کے بعد سورۂ بقرہ شروع ہوئی تو ابتدا میں ہی کہہ دیا گیا کہ الٓمّٓ.ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ١ۛۖۚ فِيْهِ١ۛۚ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ۠ گویا سورۃ فاتحہ میں جو ہدایت طلب کی گئی تھی سورۂ بقرہ کے شروع میں اس ہدایت کی نسبت بتا دیا کہ جو کچھ تم مانگ رہے تھے وہ یہ ہے اس قسم کے تعلقات جو باہم سورتوں میں پائے جاتے ہیں قریبی تعلق کہلاتے ہیں.لیکن سورتوں کا ایک تعلق سارے مضمون کے لحاظ سے ہوتا ہے اور مسلسل ایک قسم کا مضمون کئی سورتوں میں چلتا چلا جاتا ہے.اس تعلق کے لحاظ سے اگر سورتوں پر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ بعض جگہ پانچ پانچ اور بعض جگہ دس دس سورتوں کا ایک گروپ ہوتا ہے اور ان کا مضمون زنجیر کے تسلسل کی طرح آپس میں ملتا چلا جاتا ہے.چنانچہ جو مضمون اس سورۃ کو چند پچھلی سورتوں کے مجموعہ کا ایک فرد بنا دیتا ہے اس کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں اور وہ یہ ہے کہ ان چند سورتوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت دو زمانوں کے لحاظ سے بیان کی جا رہی ہے یہ مضامین سورۂ تکویر سے شروع ہیں اور ان میں بتا یا جا رہا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے محض اس زمانہ میں ہی ثبوت مہیا نہیں ہوں گے بلکہ جب بھی اسلام کمزور ہو گا اس صداقت کے ثبوت اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہیا کئے جائیں گے.اسی تسلسل میں سورۂ بروج میں بتایا گیا تھا کہ آخری زمانہ میں دنیا کی خرابی کے وقت ایک بدر پیدا ہوگا مگر چونکہ اس سے یہ شبہ پیدا ہوتا تھا کہ نورِ محمدی گو دنیا کو فائدہ دے گا مگر رہے گا اوجھل اور براہ راست نظر نہ آئے گا اس لئے اس شبہ کا ازالہ سورۂ طارق میں کیا اور بتایا کہ آنے والا موعود دو الگ الگ نام رکھے گا بدر بھی اور طارق بھی یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم کے جلا ل کو وہ براہ راست ظاہر کرے گا یہ نہیں ہو گا کہ لوگ صرف سن کر ایمان لائیں گے بلکہ وہ ایسی جماعت پیدا کرے گا جس کا خدا تعالیٰ سے براہ راست تعلق ہو گا اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم کے انوار اور آپ کی برکات اپنی ذات میں مشاہدہ کریں گے.گویا سورۂ بروج میں مسیحیت موعودہ کی پیشگوئی کی طرف اشارہ کیا گیا تھا اور سورۂ طارق میں مہدویت مبشرہ کی پیشگوئی کی طرف اشارہ کیا گیا تھا.پھر میں نے سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى اور
Page 160
سورۃ الغاشیہ کا آپس میں تعلق بتاتے ہوئے ذکر کیا تھا کہ یہ دونوں سورتیں رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم جمعہ اور عیدین کی نمازوں میں بالالتزام پڑھا کرتے تھے اور یہ دونوں سورتیں ایسی ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم کی ترقی اور آنے والے موعود کی خبر یکجائی طور پر اپنے اندر رکھتی ہیں یا اگر ایک ٹکڑہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم کا ذکر آتا ہے تو بعد کے ٹکڑہ میں آنے والے موعود کا ذکر کیا گیا ہے.یا مثال تو ایک ہی دی ہے مگر وہ مثال ایسی ہے جو وہاں بھی چسپاں ہو جاتی ہے اور یہاں بھی چسپاں ہو جاتی ہے گویا دو دھاری تلوار ہے جس سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے مخالفین پر بھی حجت تمام ہو جاتی ہے اور بعد میں پیدا ہونے والے مخالفین پر بھی حجت تمام ہو جاتی ہے.اسی سلسلہ میں مَیں نے بتایا تھا کہ اِنَّهٗ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَ مَا يَخْفٰى(الاعلٰی :۸) میں بھی آنے والے موعود کی ضرورت بیان کی گئی ہے اور خبر دی گئی ہے کہ اس زمانہ میں قرآن کریم کا ظاہر تو باقی ہو گا مگر اس کا مغز نہیں ہو گا.تب اس موعود کے ذریعہ اللہ تعالیٰ قرآنی علوم کو دنیا میں پھر زندہ کرے گا اور پھر اس کے مغز کو دنیا میں واپس لائے گا.اسی طرح وُجُوْہٌ يَّوْمَىِٕذٍ خَاشِعَۃٌ عَامِلَۃٌ نَّاصِبَۃٌ میں دونوں زمانوں کی مخالفت اور اسلام کی ترقی کا ذکر کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ جب بھی اسلام پر کمزوری کا زمانہ آئے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کمزوری کو دور کرنے کا سامان کیا جائے گا.اسلام اور مسلمانوں کی ترقی اگر ہو سکتی ہے تو اسی ذریعہ سے، اس کے بغیر ان کی ترقی کا کوئی ذریعہ نہیں.یہ مضمون ہے جو مسلسل کئی سورتوں سے چلا آ رہا ہے اور جس کی وجہ سے ہر سورۃ اپنے سے پہلی سورۃ سے بالکل مربوط نظر آتی ہے.سورۃ الفجر کاتعلق پہلی سورۃ سے وہ گہرا تعلق جو اس سورۃ کو پہلی سورۃ سے حاصل ہے یہ ہے کہ پہلی سورۃ میں بتایا گیا تھا کہ اسلام کا مقابلہ کفارِ مکہ کریں گے اور ہر قسم کی تدابیر اسلام کے خلاف کریں گے لیکن کامیاب نہ ہوں گے بلکہ ان کے مقابل پر مسلمان کامیاب ہوں گے.دوسرے یہ بتایا تھا کہ آئندہ بھی اسلام پر جب کبھی خطرناک وقت آئے گا خدا تعالیٰ اسلام کی مدد کرے گا اور اُ س کے مخالف آخر شکست کھائیں گے.اس سورۃ میں اس مضمون کی مزید وضاحت کی گئی ہے اور تفصیل بھی بیان کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ وہ وُجُوْہٌ جو خَاشِعَۃٌ عَامِلَۃٌ نَّاصِبَۃٌ کے مصداق ہوں گے کس طرح عمل اور محنت کریں گے اور کس طرح اللہ تعالیٰ ان وُجُوْہ کو دنیا میں پیدا کرے گا جو نَاعِـمَةٌ لِّسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ کے مصداق ہوں گے.ظاہر ہے کہ نبوت کے تیسرے سال میں تو یہ دونوں وُجُوْہ پوشیدہ تھے نہ خَاشِعَۃٌ عَامِلَۃٌ اور نہ نَاصِبَۃٌ پائے جاتے تھے کیونکہ منظم مخالفت ابھی کفارِ مکہ نے شروع نہیں کی تھی اور نہ یہ پتہ تھا کہ نَاعِـمَةٌ وُجُوْہ کون ہوں گے اور کہاں سے آئیں گے کیونکہ مومنوں کی تعداد
Page 161
گنتی کے چند افراد پر مشتمل تھی.ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ اس سورۃ میں پیشگوئی فرماتا ہے کہ کفار کی مخالفت کیسا شدید رنگ اختیار کرے گی اور کس طرح مسلمانوں کی ترقی اور رفعت ہو گی.اسی طرح بعد میں جب خود مسلمان بگڑیں گے اور اسلام سے دور ہو جائیں گے تو اس وقت خدا تعالیٰ کس رنگ میں اپنی نصرت ظاہر کرے گا.میں اس مقام پر اللہ تعالیٰ کی تائید کے ایک تازہ واقعہ کا ذکر کئے بغیر نہیں رہ سکتا قرآن کریم کے سینکڑوں بلکہ ہزاروں مضامین ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل سے القاء اور الہام کے طور پر مجھے سمجھائے ہیں اور میں اس بارہ میں اللہ تعالیٰ کے انعامات کا جس قدر بھی شکر ادا کروں کم ہے.اس نے کئی ایسی آیات جو مجھ پر واضح نہیں تھیں ان کے معانی بطور وحی یا القاء میرے دل پر نازل کئے اور اس طرح اپنے خاص علوم سے اس نے مجھے بہرہ ور کیا.مثال کے طور پر میں سورۂ بقرہ کی ترتیب کو پیش کرتا ہوں.میں ایک دن بیٹھا ہوا تھا کہ یک دم مجھے القاء ہوا کہ فلاں آیت اس کی کنجی ہے اور جب میں نے غور کیا تو اس کی تمام ترتیب مجھ پر روشن ہو گئی.اسی طرح سورۂ فاتحہ کے مضامین مجھے القاء ً اور الہاماً اللہ تعالیٰ کی طرف سے رؤیا میں بتائے گئے تھے.اس کے بعد خدا تعالیٰ نے میرا سینہ سورۂ فاتحہ کے حقائق سے لبریز فرما دیا.قرآن کریم کی ترتیبیںبیسیوں آیا ت کے متعلق خدا تعالیٰ کی طرف سے بطور القاء مجھے سمجھائی گئی ہیں مثلاً سورۂ بروج اور سورۂ طارق کا یہ جوڑ کہ ان میں سے ایک سورۃ میں مسیحیت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور دوسری سورۃ میں مہدویت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے.یہ بھی ان مضامین میں سے ہے جو لوگوں کی نگاہ سے مخفی تھے مگر اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعہ ان کو ظاہر فرمایا اور مجھے وہ دلائل دیئے جن سے میں اپنے اس استدلال کو پوری قوت کے ساتھ ثابت کر سکتا ہوں اور کوئی منصف مزاج ان دلائل کو تسلیم کرنے سے انکار نہیں کر سکتا.عقلی طور پر اسے بہرحال ماننا پڑے گا کہ میرا دعویٰ دلائل پرمبنی ہے یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ کہہ دے کہ میں ان دلائل کو تسلیم نہیں کرتا لیکن اسے یہ ضرور ماننا پڑے گا کہ میں نے جو دعویٰ کیا ہے اس کے دلائل اور وجوہ موجود ہیں.غرض قرآن کریم کی کئی مشکل آیات کے معانی اللہ تعالیٰ نے اپنے القاء اور الہام کے ذریعہ مجھ پر منکشف فرمائے ہیں اور اس قسم کی بہت سی مثالیں میری زندگی میں پائی جاتی ہیں.انہی مشکل آیات میں سے میرے لئے ایک یہ سورۃ بھی تھی.میں جب بھی سوچتا اور غور کرتا مجھے اس کے معانی کے متعلق تسلی نہیں ہوتی تھی بلکہ ہمیشہ دل میں ایک خلش سی پائی جاتی تھی اور مجھے بار بار یہ خیال پیدا ہوتا تھا کہ جو معانی بتائے جاتے ہیں وہ قلب کو مطمئن کرنے والے نہیں.اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مفسرین نے بہت سے معانی کئے ہیں جو لوگوں کی نگاہ میں اس سورۃ کو
Page 162
حل کر دیتے ہیں مگر میری اپنی نگاہ میں وہ اطمینان بخش معانی نہیں تھے اور اس لئے ہمیشہ ایک بے چینی سی میرے اندر پائی جاتی تھی میں سوچتا اور غور کرتا مگر جو بھی معنے میرے ذہن میں آتے جن کو مزید غور کے بعد میں خود ہی ردّ کر دیتا کہ کہتا کہ یہ درست نہیں ہیں آخر بڑی مدتوں کے بعد ایک دفعہ جب میں عورتوں میں قرآن کریم کے آخری پارہ کا درس دینے لگا تو اس کا ایک حصہ حل ہو گیا مگر پھر بھی جو حل ہوا وہ صرف ایک حصہ ہی تھا مکمل مضمون نہیں تھا جو معنے مجھ پر اس وقت روشن ہوئے ان سے چاروں کھونٹے قائم نہیں ہوتے تھے دو۲ تو بن جاتے تھے مگر دو۲ رہ جاتے تھے یہ حالت چلتی چلی گئی اور مجھے کامل طور پر اس کے معانی کے متعلق اطمینان حاصل نہ ہوا.اب جو میں نے درس دینا شروع کیا تو پھر یہ سورۃ میرے سامنے آ گئی اور میں نے اس پر غور کرنا شروع کردیا.میں نے آخری پارے کا درس جولائی ۱۹۴۴ء میں شروع کیا تھا اور ڈلہوزی میں اس کی ابتدا کی تھی اس وقت سے لے کر اب تک کئی دفعہ میں نے اس سورۃ پر نظر ڈالی اور مجھے سخت فکر ہوا کہ اس سورۃ کا درس تو قریب آ رہا ہے مگر ابھی اس کے معانی ترتیبِ سُوَر کے لحاظ سے مجھ پر روشن نہیں ہوئے.بار بار میں اس سورۃ کو دیکھتا.اس کے مطالب پر غور کرتا اور کوئی مضمون میرے ذہن میں بھی آ جاتا مگر پھر سوچتے سوچتے میں اس کو ناکافی قرار ددے دیتا غرض بیسیوں دفعہ میں نے اس سورۃ پر نگا ہ دوڑائی مگر مجھے اپنے مقصد میں کامیابی نہ ہوئی یہاں تک کہ سورۃ الغاشیہ کے درس کا وقت آ گیا اور میں اس کے نوٹ لکھنے لگا مگر اس وقت بجائے غاشیہ پر نگاہ ڈالنے کے میری نظر بار بار آگے کی طرف نکل جاتی اور سورۃ الفجر میرے سامنے آ جاتی.غاشیہ کے متعلق میں سمجھتا کہ یہ تو حل شدہ ہی ہے اور اگر کوئی مشکل آیت بھی ہوئی تو ترتیب میں آ کر وہ خودبخود حل ہو جائے گی.جس طرح ایک انسان جب گیند پھینکتا ہے تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ گیند اتنی دور جائے گا.اسی طرح جو شخص قرآن کریم کی تفسیر ترتیبِ آیات اور ترتیبِ سُوَر کو مدنظر رکھ کر کرتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس ترتیب کے مطابق فلاں آیت کے معنے فلاں بنیں گے مگر اس بات کو وہی شخص سمجھ سکتا ہے جس نے اپنی عمر اس فن میں صرف کر دی ہو.وہی جانتا ہے کہ نہر کا رخ کس طرف ہے اور پانی کا بہاؤ کدھر ہے دوسرا شخص جسے قرآن پر اس رنگ میں غور کرنے کا موقع نہ ملا ہو وہ ان باتوں کو نہیں سمجھ سکتا.جب میں سورۂ کہف کی تفسیر لکھ رہا تھا تو لَا تَقُوْلَنَّ لِشَايْءٍ اِنِّيْ فَاعِلٌ ذٰلِكَ غَدًا.اِلَّاۤ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ (الکہف:۲۴،۲۵) کے معنے میری سمجھ میں نہیں آتے تھے مگر تفسیر لکھتے وقت میں نے سمجھا کہ میں صحیح ترتیب پر چل رہا ہوں جب میں اس آیت پر پہنچوں گا تو دیکھوں گا کہ اس کے کیا معنے بنتے ہیں چنانچہ ترتیبِ آیات کو مدنظر رکھتے ہوئے میں تفسیر کرتا چلا گیا یہاں تک کہ جب میں اس آیت پر پہنچا تو اس وقت یہ آیت اپنے معانی کے لحاظ سے یوں واضح ہو گئی کہ میں
Page 163
نے سمجھ لیا کہ اس کے سوا اس آیت کے اور کوئی معنے ہو ہی نہیں سکتے کیونکہ پہلی آیتیں مجبور کر کے ان معنوںکی طرف لے جا رہی تھیں.لطیفہ یہ ہوا کہ انگریزی ترجمۃ القرآن کے سلسلہ میں مولوی شیر علی صاحب کے نوٹ جب میرے پاس آئے تو ان میں وہی معنے لکھے ہوئے تھے مگر وہ نوٹ انہوں نے یہاں نہیں لکھے تھے بلکہ ولایت میں لکھے تھے میں نے ملک غلام فرید صاحب سے پوچھا کہ مولوی صاحب نے یہ نوٹ اب ٹھیک کئے ہیں یا پہلے سے اسی طرح لکھے ہوئے تھے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ ولایت کے لکھے ہوئے ہیں میں نے کہا اگر یہ ولایت کے نوٹ ہیں تو پھر اس آیت کے یہ معنے ولایت میں کس طرح پہنچ گئے؟ میں تو اس آیت پر بڑا غور کرتا رہا تھا مگر اس کے معنے پندرھویں پارہ کی تفسیر لکھتے ہوئے میری سمجھ میں آئے تھے.اس پر انہوں نے بتایا کہ آپ نے جو درس ۱۹۲۲ء میں دیا تھا اس میں یہی معنے بیان کئے تھے اور اسی وقت کے نوٹوں سے مولوی صاحب نے یہ معنے درج کئے ہیں.معلوم ہوتا ہے ۱۹۲۲ء کا درس دیتے وقت جب میں اس آیت پر پہنچا تو خود بخود یہ آیت حل ہو گئی مگر چونکہ عین وقت پر حل ہوئی اس لئے میرے قرآن کریم کے حاشیہ پر وہ معنے نہ لکھے گئے اور کچھ عرصہ بعد مجھے بھول گئے.اب گو ان معنوں کو میں بھول چکا تھا مگر جب ترتیب آیات کے لحاظ سے غو کرتے ہوئے میں اس آیت پر پہنچا تو فوراً وہی معنے پھر ذہن میں آ گئے.تو ترتیب کے لحاظ سے جو شخص آیات کے معنے کرنے کا عادی ہو وہ ادھر ادھر جا ہی نہیں سکتا.وہ اسی رَو اور اسی نالی میں بَہہ رہا ہوتا ہے جس کی طرف مضمون زبانِ حال سے اشارہ کر رہا ہوتا ہے.غرض جوں جوں سورۂ فجر کا درس نزدیک آتا گیا میرا اضطراب بھی بڑھتا چلا گیا.میں نے کہا جب اس سورۃ کے متعلق میری اپنی تسلی ہی نہیں ہوئی تو میں دوسروں کو کیسے مطمئن کر سکتا ہوں.مفسرین نے جو معنے بیان کئے ہیں وہ میں بیان کر سکتا تھا مگر جو ترتیب گذشتہ سورتوں سے میں بتاتا آ رہا ہوں اس کے لحاظ سے چاروں کھونٹے قائم نہیں ہوتے تھے.پہلے خیال آیا کہ میں دوسروں کے معانی ہی نقل کر دوں کیونکہ یہ درس اب جلد کتابی صورت میں چھپنے والا ہے کب تک میں ان معانی کا انتظار کروں جو ترتیب کے مطابق ہوں شاید ترتیب کے مطابق معنے اللہ تعالیٰ پھر کسی وقت کھول دے آخر پرانے مفسروں نے کوئی نہ کوئی معنے ان آیات کے کئے ہی ہیں.رازی نے بھی ان کے معنے لکھے ہیں.بحرِ محیط والوں نے بھی معنے لکھے ہیں.حضرت خلیفۂ اوّل رضی اللہ عنہ نے بھی معنے کئے ہوئے ہیں اور ان تمام معانی کو ملحوظ رکھ کر کچھ نہ کچھ بات بن ہی جاتی ہے مگر چونکہ میرا دل کہتا تھا کہ ترتیب آیات کو مدنظر رکھتے ہوئے وہ معانی پوری طرح باہم منطبق نہیں ہوتے مجھے اطمینان نہ ہوا.یہاں تک کہ ۱۷؍ ماہ صلح ۱۳۲۴ہش مطابق ۱۷؍ جنوری۱۹۴۵ء بروز بدھ میں سورۂ غاشیہ کا درس دینے کے لئے مسجد مبارک میں آیا.میں نے درس
Page 164
سورۂ غاشیہ کا دینا تھا مگر میں غور سورۂ فجر پر کر رہا تھا اسی ذہنی کشمکش میں مَیں نے عصر کی نماز پڑھانی شروع کی اور میرے دل پر ایک بوجھ تھا لیکن خدا تعالیٰ کی قدرت ہے کہ جب میں عصر کی نماز کے آخری سجدہ سے سر اٹھا رہا تھا تو ابھی سر زمین سے ایک بالشت بھر اونچا آیا ہو گا کہ ایک آن میں یہ سورۃ مجھ پر حل ہو گئی.پہلے بھی کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ سجدہ کے وقت خصوصًا نماز کے آخری سجدہ کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے بعض آیات کو مجھ پر حل کر دیا.مگر اس دفعہ بہت ہی زبردست تفہیم تھی کیونکہ وہ ایک نہایت مشکل اور نہایت وسیع مضمون پر حاوی تھی چنانچہ جب میں نے عصر کی نماز کا سلام پھیرا تو بے تحاشہ میری زبان سے اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ کے الفاظ بلند آواز سے نکل گئے.بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۰۰۱ (میں) اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا (اور) بار بار رحم کرنے والا ہے (شروع کرتا ہوں).وَ الْفَجْرِۙ۰۰۲ وَ لَيَالٍ عَشْرٍۙ۰۰۳ وَّ الشَّفْعِ وَ الْوَتْرِۙ۰۰۴ (مجھے) قسم ہے (ایک آنےوالی) فجر کی اور دس راتوں کی اور ایک جفت کی اور ایک وتر کی وَ الَّيْلِ اِذَا يَسْرِۚ۰۰۵ اور (مذکورہ بالا دس راتوں کے بعد آنے والی) رات کی جب وہ چل پڑے.حلّ لُغات.یَسْـر: سَـرَا کا مضارع ہے اور سَـرٰی کے معنے ہیں.رات کو چلا (اقرب ) پس وَالَّیْلِ اِذَایَسْرِ کے معنے ہوں گے رات جب چل پڑے.تفسیر.پیشتر اس کے کہ میں وہ معانی بتاؤں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہامی طور پر مجھے سمجھائے گے ہیں میں پہلے دوسرے لوگوں کے بیان کردہ معنے بتانا چاہتا ہوں تاکہ میری مشکلات کا دوستوں کو پتہ لگ جائے اور ان کو معلوم ہو کہ میری مشکلات حقیقی مشکلات تھیں.اگر میں شرح صدر کے بغیر جو مجھے اب حاصل ہے اس کے معنے بتا دیتا تو میں اپنے نفس میں تسلی نہیں پا سکتا تھا.یہ مضمون میں چار آیات کے متعلق مشترک طور پر بیان کر رہا ہوں.یہ آیات یہ ہیں (۱) وَالْفَجْرِ (۲) وَلَیَالٍ عَشْرٍ (۳)وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ (۴)وَالَّیْلِ اِذَایَسْرِ.ان آیات میں چار قسمیں کھائی گئی ہیں اور قسم کے معنے شہادت کے ہوتے ہیں یہ مضمون تفصیل کے ساتھ
Page 165
پہلے آچکا ہے اس کے اعادہ کی ضرورت نہیں.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں فجر کو شہادت کے طور پر پیش کرتا ہوں اسی طرح میں دس عظیم الشان راتوں کو شہاد ت کے طور پر پیش کرتا ہوں نیز میں شفع اور وتر کو شہادت کے طور پر پیش کرتا ہوں.شفع اور وتر کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ ان میں سے کوئی چیز طاق ہے اور کوئی چیز جفت ہے کیونکہ وتر طاق کو کہتے ہیں اور شفع جفت کو.اسی طرح فرماتا ہے میں رات کو شہادت کے طور پر پیش کرتا ہوں جب وہ چلی جائے گی.اس جگہ چار قسمیں کھائی گئی ہیں سوال یہ ہے کہ ان سے مراد کیا ہے اور کس چیز کو کس چیز کی شہادت کے لئے پیش کیا گیا ہے.فجر کیا چیز ہے اور وہ کس امر کی شہادت دے رہی ہے.لَیَالٍ عَشْرٍ کیا چیز ہیں اور کون سی دس راتیں یہاں مراد ہیں اور وہ کس امر کے ثبوت کے لئے بطور شاہد پیش کی گئی ہیں.شفع اور وتر کیا چیز ہیں اور انہیں کس بات کے ثبوت کے لئے پیش کیا گیا ہے اسی طرح رات جو جانے والی ہے کون سی ہے اور اسے کس بات کے ثبوت کے لئے پیش کیا گیا ہے؟ الفجر حضرت علیؓ، ابن عباسؓ، عکرمہ، مجاہد اور سدی کا قول ہے کہ فجر سے مراد وہ معروف صبح ہے جو رات کے بعد آتی ہے ( تفسیر ابن کثیر زیر آیت ’’وَ الْفَجْرِ وَ لَيَالٍ عَشْرٍ‘‘) مسروق اور محمد بن کعب کا قول ہے کہ اس سے مراد یوم نحر کی صبح ہے ( تفسیر ابن کثیر زیر آیت ’’وَ الْفَجْرِ وَ لَيَالٍ عَشْرٍ‘‘) گویا صبح سے وہ صبح ہی مراد لیتے ہیں مگر کہتے ہیں اس سے ہر صبح مراد نہیں بلکہ قربانی کے دن سے پہلے جو صبح آتی ہے وہ مراد ہے اور وہ دس راتوں کی آخری فجر ہے کیونکہ عید دسویں تاریخ کو ہوتی ہے پس ان کے نزدیک فجر سے مراد ذوالحجہ مہینہ کی دس راتوں کی آخری فجر ہے.عکرمہ کہتے ہیں کہ فجر سے مراد وہ صبح کی نماز ہے جو دسویں ذوالحجہ کو پڑھی جاتی ہے یعنی عید کے دن کی صبح کی نماز.گویا یہ بھی انہی معنوں کی طرف گئے ہیں جو مسروق اور محمد بن کعب نے کئے ہیں صرف فرق یہ ہے کہ وہ اس سے ذوالحجہ کی دسویں تاریخ کی فجر مراد لیتے ہیں اور یہ فجر کی نمازمراد لیتے ہیں یا کہتے ہیں کہ فجر سے تہجد کی نماز بھی مراد ہوسکتی ہے اور ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ فجر سے مراد سارا دن بھی ہو سکتا ہے ان معنوں کے رو سے بھی ذوالحجہ کی دسویں تاریخ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے صرف یہ فرق ہے کہ فجر سے پَو پھٹنے سے لے کر سورج نکلنے تک کا وقت مراد نہیں لیا گیا.بلکہ پَو پھٹنے سے لے کر شام تک عید کا سارا دن مراد لیا گیا ہے یعنی عید کا سارا دن.( تفسیر ابن کثیر زیر آیت ’’وَ الْفَجْرِ وَ لَيَالٍ عَشْرٍ‘‘) لَیَالٍ عَشْرٍ.دوسرا سوال یہ ہے کہ دس راتوں سے کیا مراد ہے ابن عباس کا قول ہے کہ دس راتوں سے
Page 166
مراد ذوالحجہ کی راتیں ہیں عید سے پہلے کی.عبداللہ بن زبیرؓ، مجاہد اور کئی علماء سلف نے یہی بات کہی ہے.اسی طرح بہت سے بعد کے علماء کا بھی یہی قول ہے.ترمذی میں حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ مَا مِنْ اَیَّامٍ اَلْعَمَلُ الصَّالِـحُ فِیْـھِنَّ اَحَبُّ اِلَی اللّٰہِ مِنْ ھٰـــذِہِ الْاَیَّـامِ الْعَشْـرِ (یعنی ذی الحجہ) ( جامع ترمذی ابواب الصوم باب ما جاء فی العمل فی ایّام العشـر) یعنی عمل صالح کے لحاظ سے یوں تو جس دن بھی کوئی شخص نیکی کرے اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کر سکتا ہے مگر وہ ایام جن میں نیکی کی خاص طور پر قدر کی جاتی ہے اور جن میں عمل صالح کرنا اللہ تعالیٰ کو خاص طور پر پسند آتا ہے ان میں سے کوئی بھی دن اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب نہیں جتنا ان دس دنوں یعنی عشرہ ذی الحجہ میں نیک اعمال بجا لانا اس کو پسند ہے.قَالُوْا یَارَسُوْلَ اللہِ وَلَا الْـجِھَادُ فِیْ سَبِیْلِ اللہِ؟ فَقَالَ وَلَا الْـجِھَادُ فِیْ سَبِیْلِ اللہِ.لوگوں نے کہا کہ کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی ان دنوں کے اعمال سے اچھا نہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ جہاد فی سبیل اللہ بھی ان دنوں کے اعمال سے زیادہ اچھا نہیں.اِلَّارَجُلًا خَرَجَ بِنَفْسِہٖ وَمَالِہٖ ثُمَّ لَمْ یَرْجِعْ مِنْ ذَالِکَ بِشَیْءٍ (تفسیر ابن کثیر زیر آیت ’’وَ لَيَالٍ عَشْرٍ‘‘) سوائے اس کے کہ کوئی شخص اپنی جان اور اپنا مال لے کر خد ا تعالیٰ کی راہ میں نکلے اور پھر مارا بھی جائے اور اس کا سارا مال بھی ضائع ہو جائے اس کے متعلق ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس نے ایسا نیک عمل کیا جو ان ایام کے اعمال صالحہ کے برابر ہے ورنہ اور کوئی عمل ان دس ایام کے اعمال کے برابر نہیں ہو سکتا.ابو جعفر ابن جریر کہتے ہیں کہ دس راتوں سے مراد محرم کی پہلی راتیں ہیں.(تفسیر ابن کثیر زیر آیت ’’وَ لَيَالٍ عَشْرٍ‘‘) ابو ظبیان حضرت ابن عباسؓ سے روایت کرتے ہیں کہ ان سے مراد رمضان کی پہلی دس راتیں ہیں (تفسیر ابن کثیر زیر آیت ’’وَ لَيَالٍ عَشْرٍ‘‘) گویا لَیَالٍ عَشْرٍ کے متعلق تین خیالات پائے جاتے ہیں.۱.کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ذوالحجہ کی عید سے پہلے کی دس راتیں ہیں.۲.کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد محرم کی پہلی دس راتیں ہیں.۳.کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد رمضان کی پہلی دس راتیں ہیں.ابن الزبیر جابرؓ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم نے فرمایا کہ دس سے مراد قربانی کے مہینہ کی دس راتیں ہیں (گویا یہ روایت انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دی کہ لَیَالٍ عَشْرٍ سے ذوالحجہ کی دس راتیں مراد ہیں) اور وتر یومِ عرفہ ہے.(کیونکہ وہ نویں دن ہوتا ہے) اور شفع یومِ نحر ہے یعنی عید کا دن(تفسیر ابن کثیر زیر آیت ’’وَ لَيَالٍ عَشْرٍ‘‘) یہ روایت امام احمد سے ابن کثیر نے نقل کی ہے.نسائی نے بھی یہ
Page 167
روایت محمد بن رافع اور عبدۃ بن عبداللہ سے نقل کی ہے جن دونوں نے زید بن الحباب سے سنا ہے.یہ وہی راوی ہیں جن سے براہ راست امام احمد نے روایت کی ہے.ابن جریر اور ابن ابی حاتم کی روایات بھی زید بن الحباب تک پہنچتی ہیں (تفسیر ابن کثیر زیر آیت ’’وَ لَيَالٍ عَشْرٍ‘‘) گویا چاروں کتب احادیث میں زید بن الحباب کی طرف یہ روایت منسوب ہے گویا نیچے کے راوی خواہ مختلف ہوں زید بن الحباب پر پہنچ کر روایت کا سلسلہ ایک ہو جاتا ہے اس لئے یہ روایت احاد میں سے ہے.ابن کثیر جو حدیث کے بہت بڑے عالم ہیں وہ اس روایت کو درج کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ میرے نزدیک اس حدیث کو مرفوع قرار دینے میں مجھے شبہ ہے یعنی اس روایت کو رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم تک پہنچانا یقینی معلوم نہیں ہوتا.شفع اور وتر ابن عباس کا قول ہے کہ وتر یومِ عرفہ ہے یعنی ذوالحجہ کا نواں دن جو حج کا دن ہے اور طاق ہے اور شفع یوم النحر ہے یعنی قر بانی کا دن جو دسواں ہے اور جفت ہے.عکرمہ اور ضحاک کا بھی یہی قول ہے (تفسیر ابن کثیر زیر آیت ’’وَالشَّفْعِ وَ الْوَتْرِ‘‘) اور ابن ابی حاتم کی روایت ہے کہ واصل بن سائب کہتے ہیں میں نے عطا سے پوچھا کیا شفع والوتر سے مراد ہماری نماز وتر ہے؟ انہوں نے کہا وتر کی نماز مراد نہیں بلکہ شفع سے مراد یوم العرفہ ہے (مگر وہ نواں اور طاق ہے نہ کہ جفت) اور وتر سے مراد یوم الاضحیہ کی رات ہے (تفسیر ابن کثیر زیر آیت ’’وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ‘‘) اور یہ رات دسویں اور جفت ہے نہ کہ طاق.معلوم ہوتا ہے کہ راوی سے اس میں غلطی ہو گئی ہے یا ابن کثیر سے نقل کرتے ہوئے غلطی ہو ئی ہے.ابن ابی حاتم روایت کرتے ہیں کہ مجھ سے محمد بن عامر بن ابراہیم الاصبہانی نے روایت کی انہوں نے اپنے باپ ابراہیم الاصبہانی سے روایت کی انہوں نے النعمان یعنی ابن عبدالسلام سے روایت کی کہ ان سے مکہ میں سعید بن عوف نے روایت کی میں نے ایک دفعہ عبداللہ بن زبیر کو تقریر کرتے سنا (آپ کے ایام خلافت میں مکہ مکرمہ کے مقام پر) تقریر کے دوران میں ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا اے امیر المومنین (یزید کے وقت میں حضرت عبد اللہ بن زبیر نے اس کی بیعت سے انکار کر دیا تھا اور مکہ میں اپنی خلافت کا اعلان کر دیا تھا یہ اس وقت کی بات ہے عبداللہ بن زبیر حضرت ابو بکر کے نواسے اور حضرت زبیر بن العوام کے فرزند تھے) شفع اور وتر کے متعلق مجھے کچھ سمجھائیے.حضرت عبداللہ بن زبیر نے جو علاوہ صحابی ہونے کے بہت عبادت گذار بزرگ تھے اور بہت سے لوگوں نے ان کو پہلا مجدّد قرار دیا ہے اور بعض نے مہدی.انہوں نے جواب میں فرمایا شفع سے مراد
Page 168
فَمَنْ تَعَجَّلَ فِيْ يَوْمَيْنِ فَلَاۤ اِثْمَ عَلَيْهِ ہے اور وتر سے مراد وَمَنْ تَاَخَّرَ فَلَاۤ اِثْمَ عَلَیْہِ ہے (تفسیر ابن کثیر زیر آیت ’’وَالشَّفْعِ وَ الْوَتْرِ‘‘) یعنی قرآن کریم میں جو یہ ذکر آتا ہے کہ جب تم حج کر چکو تو چاہے دو دن ٹھہر کر آ جاؤ یا تین دن.اس میں دو دن ٹھہر کر آنا شفع ہوا.اور یہ جو فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص تیسرے دن بھی ٹھہرنا چاہے تو اسے اجازت ہے یہ تیسرا دن وتر ہے.ابن جریر نے بھی یہ روایت حضرت عبداللہ بن زبیر سے نقل کی ہے.بخاری اور مسلم میں روایت ہے کہ ابوھریرہؓ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ننانو۹۹ے نام ہیں یعنی سو میں سے ایک کم جو شخص ان کو خوب گن رکھے وہ جنت میں داخل ہو گا اور اللہ وتر ہے وتر کو پسند کرتا ہے (صحیح مسلم کتاب الذکر و الدعاء والتوبۃ و الاستغفار باب فی اسماء اللہ تعالیٰ و فضل من احصاھا) یعنی اللہ تعالیٰ بھی ایک ہے اور اس نے اپنے نام بھی ننانوے ہی رکھے ہیں اس حدیث کا اصل مطلب یہ ہے کہ صفاتِ الٰہیہ کا گہرا مطالعہ انسان کو حقیقی متقی بناتا ہے تقویٰ کے معنے بھی یہی ہوتے ہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کی صفات کو اپنے اندر پیدا کر لے جو شخص اللہ تعالیٰ کی ساری صفات کو اپنے مدنظر رکھے گا وہ کسی خوبی کو نظر اندا ز نہیں کر سکتا اور جو شخص ہر خوبی کو اپنے سامنے رکھے گا اور ہر نیکی پر عمل کرے گا اس کے یقینی جنتی ہونے میں شبہ ہی کیا ہو سکتا ہے.حسن بصری اور زید بن اسلم کہتے ہیں کہ تمام مخلوق یا شفع ہے یا وتر.اس لئے اللہ تعالیٰ نے یہاں مخلوق کی قسم کھائی ہے(تفسیر ابن کثیر زیر آیت ’’وَالشَّفْعِ وَ الْوَتْرِ‘‘).مجاہد سے بھی یہی مروی ہے اور وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ شفع اور وتر سے مخلوق مراد ہے کیونکہ کوئی جوڑا ہوتا ہے اور کوئی اکیلا.ابن عباسؓ سے عوفی نے روایت کی ہے کہ اللہ وتر ہے اور تم لوگ شفع ہو کیونکہ تم نر ومادہ ہوتے ہو اور خدا اکیلا ہے اس لئے تم تو شفع ہو اور خدا وتر ہے بعض نے کہا ہے کہ شفع سے مراد صبح کی نماز ہے اور وتر سے مراد شام کی نماز (تفسیر ابن کثیر زیر آیت ’’وَالشَّفْعِ وَ الْوَتْرِ‘‘).ابن ابی حاتم نے مجاہد سے روایت کی ہے کہ شفع سے مراد جوڑا ہے اور وتر اللہ تعالیٰ ہے(تفسیر ابن کثیر زیر آیت ’’وَالشَّفْعِ وَ الْوَتْرِ‘‘) یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ اَنَّهٗ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَ الْاُنْثٰى.مِنْ نُّطْفَةٍ اِذَا تُمْنٰى (النجم:۴۶،۴۷) اسی کی طرف شفع میں اشارہ کیا گیا ہے.ابو عبداللہ مجاہد سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ وتر ہے اور مخلوق شفع ہے کیونکہ وہ ذکر وانثیٰ ہوتی ہے.(تفسیر ابن کثیر زیر آیت ’’وَالشَّفْعِ وَ الْوَتْرِ‘‘) ابن ابی نجیع مجاہد سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا کیا ہے جوڑا ہے اور اس سے آپ نے اس آیت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ (الذاریات:۵۰) چونکہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر مخلوق کو جوڑے کی صورت میں پیدا کیا گیا ہے اس لئے
Page 169
شفع سے مراد مخلوق اور وتر سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے(تفسیر ابن کثیر زیر آیت ’’وَالشَّفْعِ وَ الْوَتْرِ‘‘).قتادہ حسن بصری سے روایت کرتے ہیں کہ شفع اور وتر سے مراد عدد ہیں کہ وہ شفع اور وتر ہوتے ہیں (تفسیر ابن کثیر زیر آیت ’’وَالشَّفْعِ وَ الْوَتْرِ‘‘) مثلاً ایک۱ وتر ہے دو۲ شفع ہے تین۳ وتر ہے چا۴ر شفع ہے اسی طرح جس قدر عدد گنتے چلے جاؤ ان میں سے ایک شفع ہو گا اور ایک وتر.پس ان کے نزدیک شفع اور وتر میں اعداد کی طرف اشارہ کیاگیا ہے.ابن جریر نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ عبداللہ بن زبیر جابر سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اَلشَّفْعُ اَلْیَوْمَانِ وَالْوَتْرُ اَلْیَوْمُ الثَّالِثُ (تفسیر ابن کثیر زیر آیت ’’وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ‘‘) یعنی وہی جو ابن زبیر نے بیان کیا تھا کہ شفع میں فَمَنْ تَعَجَّلَ فِيْ يَوْمَيْنِ فَلَاۤ اِثْمَ عَلَيْهِ کی طرف اشارہ ہے اور وتر میں وَ مَنْ تَاَخَّرَ فَلَاۤ اِثْمَ عَلَيْهِ کی طرف.وہی بات اس روایت میں بیان کی گئی ہے.مگر یہ روایت خود ان کی پہلی روایت کے خلاف ہے جس میں وہ یہ بیان کر چکے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ شفع یومِ نحر ہے اور وتر یومِ عرفہ.ابو العالیہ اور ربیع بن انس کہتے ہیں کہ اس سے مراد نماز ہے کہ اس میں سے کوئی شفع ہوتی ہے اور کوئی وتر ہوتی ہے.مغرب کی فرض نماز وتر ہے اسی طرح وتر کی نماز اس میں شامل ہے لیکن باقی سب نمازیں شفع ہیں کیونکہ ان میں سے کسی کی دو دو رکعت ہوتی ہیں اور کسی کی چار چار(تفسیر ابن کثیر زیر آیت ’’وَالشَّفْعِ وَ الْوَتْرِ‘‘).امام احمد عمران بن حصین سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھِیَ الصَّلٰوۃُ بَعْضُھَا شَفْعٌ وَ بَعْضُھَا وِتْرٌ اس سے مراد نماز ہے کیونکہ کوئی نماز شفع ہوتی ہے اور کوئی وتر(مسند احمد بن حنبل حدیث عمران بن حصین).یہ تیسری روایت ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی گئی ہے مگر یہ تیسری روایت بھی پہلی دونوں روایتوں کے خلاف ہے.یہی روایت ترمذی اور ابن جریر نے بھی دوسرے سلسلہ سے بیان کی ہے اسی طرح ابوداؤد نے بھی یہی روایت کی ہے (تفسیر ابن کثیر زیر آیت ’’وَالشَّفْعِ وَ الْوَتْرِ‘‘).وَالَّیْلِ اِذَایَسْرِ وَالَّیْلِ اِذَایَسْرِکی تشریح سابق مفسرین کے نزدیک ابن عباسؓ کہتے ہیں اس کے معنے یہ ہیں کہ جب رات چلی جائے.اور ابن کثیر کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب رات آئے اس طرح اقبال النہار اور ادباراللیل کی قسم ہو گئی.گویا ابن عباس کے نزدیک تو اس میں رات کے جانے کا ذکر ہے مگر ابن کثیر کے نزدیک اس میں رات کے آنے کا ذکر ہے.رات کے جانے کا ذ کر وَالْفَجْرِ میں
Page 170
ہوچکا ہے.ان کا مطلب یہ ہے کہ جب فجر کا ذکر پہلے آ چکا ہے اور فجر ہمیشہ رات کے جانے پر ہی ہوتی ہے تو پھر اسی بات کو وَالَّیْلِ اِذَایَسْرِ کہہ کر کیوں دہرایا گیا ہے.چونکہ بلا وجہ کسی بات کو دہرا دینا لغو ہوتا ہے اور لغو بات قرآن کریم کی طرف منسوب نہیں ہو سکتی اس لئے وہ کہتے ہیں کہ یَسْرِ سے مراد اس جگہ جانے کے نہیں بلکہ آنے کے ہیں.یَسْـرِ کے معنے درحقیقت چلنے کے ہوتے ہیں اور اس میں آنے کا مفہوم بھی شامل ہے اور جانے کا مفہوم بھی شامل ہے.مگر ہم قرآن کریم کی طرف کیوں ایسی بات منسوب کریں جو لغو ہو.جب وَالْفَجْرِ میں رات کے جانے کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے تو وَالَّیْلِ اِذَا یَسْرِ میں پھر انہی معنوں کاتکرار درست نہیں ہو سکتا.پس اس کے معنے رات کے جانے کے نہیں بلکہ آنے کے ہیں چنانچہ وہ کہتے ہیں قرآن کریم نے خود دوسری جگہ فرمایا ہے وَالَّیْلِ اِذَا عَسْعَسَ.وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ (التکویر:۱۸،۱۹) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لیل اور صبح دونوں کی قسم کھا نا جائز ہے چنانچہ وَالْفَجْرِ میں رات کے جانے کی طرف اشارہ کر دیا اور وَالَّیْلِ اِذَایَسْرِ میں رات کے آنے کا ذکر کر دیا ضحاک کے قول کا بھی یہی منشاء ہے وہ کہتے ہیں وَالَّیْلِ اِذَا یَسْرِ اَیْ یَـجْرِیْ.(نوٹ:.متذکرہ بالا تمام حوالجات ابن کثیر سے ماخوذ ہیں) (تفسیر ابن کثیر زیر آیت ’’وَالشَّفْعِ وَ الْوَتْرِ‘‘).شفع اور وتر کے متعلق تین مختلف بیانات جو آنحضرت صلعم کی طرف منسوب کئے گئے ہیں یہ وہ مختلف بیانات ہیں جو ان آیا ت کے متعلق تفاسیر میں نظر آتے ہیں ان میں سے تین بیان رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم کی طرف بھی منسوب کئے گئے ہیں.اوّل یہ کہ شفع اور وتر سے ذی الحجہ کے ایام عرفہ اور نحر مراد ہیں.دوم یہ کہ شفع اور وتر سے حج کے بعد منیٰ سے واپسی کے ایام کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ واپس آنا دوسرے دن بھی جائز ہے اور تیسرے دن بھی.سوم یہ کہ شفع اور وتر سے نماز مراد ہے کہ کوئی نماز شفع ہوتی ہے اور کوئی وتر.تینوں روایتوں کا یہ اختلاف بتاتا ہے کہ ان روایتوں کو مرفوع کہنا بالکل غلط ہے آخر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفع اور وتر کی تشریح میں یہ تینوں مختلف باتیں کس طرح کہہ سکتے تھے معلوم ہوتا ہے یہ رُواۃ کی اپنی رائے ہے.انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض ذوالوجوہ حدیثوں سے یہ خیال کر لیا کہ شاید رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفع اور وتر سے یہ مراد لی ہے چنانچہ کسی نے کوئی استنباط کر لیا اور کسی نے کوئی.پس یہ رُواۃ کی اپنی رائے ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم کی طرف قطعی طور پر کسی مفہوم کو منسوب نہیں کیا جا سکتا.چنانچہ اس کا ثبوت
Page 171
حضرت ابن عمرؓ کی ایک روایت سے بھی ملتا ہے.مسند احمد، نسائی اور حاکم میں حضرت طلحہ بن عبداللہ ذکر کرتے ہیں کہ میں اور ابو سلمہ بن عبدالرحمٰن حج میں ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس گئے انہوں نے ہمیں کہا کہ یومِ عرفہ کی دوپہر کا کھانا ہمارے ہاں کھانا.میں نے ان سے کہا جناب یہ دن جو ذوالحجہ کے ہیں یہی لَیَالٍ عَشْرٍ ہیں.انہوں نے کہا تم کو کس نے بتایا.میں نے کہا بتانے کی کیا ضرورت ہے مجھے خود یقین ہے کہ اس سے مراد یہی دن ہیں.حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے کہا اگر تمہیں یقین ہے تو کسی وقت میرے پاس آنا میں تمہارے یقین کو شک میں بدل دوں گا.( تفسیر فتح البیان سورۃ الفجر زیر آیت ’’لَيَالٍ عَشْرٍ‘‘) اس سے صریح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ صحابہؓ سمجھتے تھے کہ ہم ان آیات کی تشریح میں جو کچھ کہتے ہیں یہ ہماری ذاتی رائے ہے.کسی رائے پر حتمی طور پر یقین کر لینا درست نہیں ورنہ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کی کوئی حدیث اس بارہ میں ہوتی تو حضرت عبداللہ بن عمرؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے مضمون کی نسبت یہ کیوں کہتے کہ میرے پاس آنا میں تمہارے یقین کو شک سے بدل دوں گا.واقعہ یہی ہے کہ ذوالحجہ کے دس دنوں کی فضیلت کے متعلق کئی حدیثیں آئی ہیں مگر ایسی کوئی حدیث نہیں جس سے یہ ثابت ہو کہ قرآن کریم میں لَیَالٍ عَشْرٍ کا جو ذکر آتا ہے اس سے مراد یہی دن ہیں.ان دنوں کی فضیلت سے ہم انکار نہیں کر تے.ہمیں اعتراف ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں کو بہت مبارک اور بہت بڑی اہمیت رکھنے والا قرار دیا ہے.مگر یہ ثابت نہیں ہو سکتا کہ کسی حدیث میں یہ ذکر آتا ہو کہ لَیَالٍ عَشْرٍ سے مراد یہی ایام ذوالحجہ ہیں.لَیَالٍ عَشْرٍ کے متعلق مفسرین کی رائے اب رہے لوگوں کے خیالات سو لَیَالٍ عَشْرٍ کے متعلق چار خیالات لوگوں میں پائے جاتے ہیں.۱.کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے ذوالحجہ کی دس ۱۰ راتیں مراد ہیں.۲.کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے محرّم کی دس ۱۰ راتیں مراد ہیں.۳.کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے رمضان کی پہلی دس ۱۰ راتیں مراد ہیں.۴.کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے رمضان کی آخری دس ۱۰ راتیں مراد ہیں.شفع اور وتر میں بھی بہت کچھ اختلاف ہے کچھ لوگ اس سے نماز مراد لیتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد عدد ہیں.اگر شفع اور وتر سے نماز مراد لی جائے یا اعداد مراد لئے جائیں تو ان کے ساتھ کوئی دس راتیں
Page 172
مخصوص نہیں ہو سکتیں حالانکہ یہاں شفع اور وتر سے پہلے دس راتوں کا ذ کر ہے.حضرت ابن عباسؓ کی اس روایت سے استدلال کر کے جسے میں نے آخر میں بیان کیا ہے ایک حال کے مفسر نے وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ کے معنے لیلۃ القدر اور دوسری راتوں کے کئے ہیں یا رمضان کی ان دس راتوں میںسے پہلی رات کے.(بیان القرآن ترجمہ مولوی محمد علی سورۃ الفجر) ان آراء پر نظر ڈالنے سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارہ میں کوئی امر ثابت نہیں.دوسرے خود صحابہؓ میں بھی سخت اختلاف ہے اور صاف معلوم ہوتا ہے کہ صرف اجتہاد پر تفسیر کی بنیاد رکھی گئی ہے صاحبِ شریعت سے کوئی امر ثابت نہیں اور پھر صحابہ کا اجتہاد بھی یقینی نہیں.ایک ایک صحابی نے دو دو تین تین ایسے معنے کئے ہیں جو آپس میں بالکل متضاد ہیں.کسی آیت کے دو دو بلکہ چار چار سو معنے کر لینا بھی بشرطیکہ وہ معنے ایک دوسرے کے متضاد نہ ہوں بلکہ مصدق ہوں بالکل جائز اور درست ہوتا ہے.لیکن ایسے معنے کرنا کہ اگر ایک معنے مانے جائیں تو دوسرے معنے ردّ کرنے پڑیں.دوسرے معنے تسلیم کئے جائیں تو تیسرے معنوں کو ناقابل قبول قرار دینا پڑے یہ اس امر کا ثبوت ہوتا ہے کہ خود معنے کرنے والے کے دل کو اطمینان نہیں ہوتا کبھی اس کا رجحان ایک معنوں کی طرف چلا جاتا ہے اور کبھی دوسرے معنوں کی طرف.کبھی وہ سمجھتا ہے کہ یہ معنے درست معلوم ہوتے ہیں اور کبھی خیال کرتا ہے کہ وہ معنے درست معلوم ہوتے ہیں.اسے اطمینان اور شرح صدر حاصل نہیں.پس صحابہؓ نے اس بارہ میں جو کچھ اجتہاد کیا وہ قطعی نہیں.چنانچہ ابن عمرؓ کا قول اس کا مصدق ہے.آخر وہ بھی اس آیت کے کوئی معنے کرتے ہوں گے انہوں نے جب سنا کہ ایک شخص کہہ رہا ہے کہ یقینی اور قطعی طور پر لَیَالٍ عَشْرٍ سے مراد ذوالحجہ کی دس راتیں ہیں تو انہیں حیرت ہوئی کہ یہ شخص کیا کہہ رہا ہے اور کس بناء پر اس مفہوم کو یقینی سمجھ رہا ہے گو بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ اکثر علماء سلف کا یہی قول تھا کہ لَیَالٍ عَشْرٍ سے ذوالحجہ کی دس راتوں کے سوا اور کوئی رات مراد نہیں مگر حضرت عبداللہ بن عمرؓ کا طلحہ بن عبداللہ سے یہ کہنا کہ میرے پاس آنا میں تمہیں شک ڈال دوں گا بتاتا ہے کہ اس بارہ میں جو کچھ کہا جا رہا تھا محض اجتہاد تک محدود تھا.آخر حضرت عبداللہ بن عمرؓ دین کے منکر تو نہیں تھے کہ انہوںنے اسے یہ کہا ہو کہ میں اسلام کی صداقت کے متعلق تمہیں شکوک میں مبتلا کر دوں گا.ان کا مطلب یہی تھا کہ تم جو یہ خیال کر رہے ہو کہ لَیَالٍ عَشْرٍ سے قرآن کریم نے یقینی طور پر ذوالحجہ کی دس راتوں کی طرف ہی اشارہ کیا ہے یہ درست نہیں.اگر تمہیں اتنا ہی کامل یقین ہے تو میرے پاس آنا میں تمہیں شبہ ڈال دوں گا.غرض ابنِ عمرؓ کا قول اس امر کا مصدق ہے کہ صرف اجتہاد پر اس آیت کی تفسیر کی بنیاد رکھی گئی تھی اسی طرح خود صحابہؓ اور تابعین کے شدید اختلافات بھی اس امر پر شاہد ہیں.لیکن اس کے باوجود ایک شخص کہہ سکتا ہے کہ ہم نے
Page 173
مان لیا اس بارہ میں شدید اختلافات پائے جاتے ہیں مگر تم ان میں سے کسی ایک بات کو ترجیح دے دو اور اس جھگڑے کو نپٹا دو.آخر جب ہم نے اجتہاد سے ہی اس آیت کی تفسیر کرنی ہے تو ہم ان مختلف بیانات میں سے کسی ایک کو جس کی طرف لوگوں کا زیادہ میلان پایا جاتا ہے کیوں درست تسلیم نہیں کر لیتے اور کیوں سب کو ناقابل قبول سمجھنے لگ جاتے ہیں.بے شک اختلافات ہیں لیکن اس اختلاف کو دور کرنے کا طریق یہ ہے کہ کسی ایک قول کو ترجیح دے دی جائے.سورۂ فجر کی پہلی چار آیات کی پہلے مفسرین کی تفسیر قبول نہ کئے جانے کی وجہ میرے نزدیک بھی یہ صورت بالکل ممکن تھی کہ باوجود اختلافات کے ہم کسی ایک قول کو ترجیح دے دیتے اور دوسروں کو ردّ کر دیتے مگر مشکل یہ ہے کہ اس طرح بھی قرآن کریم کی یہ آیات حل نہیں ہوتیں.میں دیکھتا ہوں کہ سب سے زیادہ زور ذی الحجہ کی دس راتوں پر دیا گیا ہے مگر اس تاویل کے ساتھ فجر کی کوئی معقول تفسیر بیان نہیں کی گئی.اگر اللہ تعالیٰ نے صرف دس راتوں کا ذکر کیا ہوتا تو ہم کہہ سکتے تھے کہ اس سے مراد ذی الحجہ کی دس راتیں ہیں مگر اللہ تعالیٰ نے دس راتوں کے ساتھ ایک فجر کا بھی ذکر کیا ہے جو ان سے پہلے ہے.وہ فرماتا ہے وَالْفَجْرِ وَلَیَالٍ عَشْرٍ ہم شہادت کے طور پر فجر کو پیش کرتے ہیں اور ہم شہادت کے طور پر اس فجر کے ساتھ دس راتوں کو پیش کرتے ہیں اگر ان دس راتوں سے مراد ذی الحجہ کی دس راتیں ہیں تو سوال یہ ہے کہ پھر فجر سے کون سی فجر مراد ہے اگر دس راتوں کی آخری فجر مراد ہے تو اس میں کس بات کی شہادت مخفی ہے کون سا اہم امر شریعت سے تعلق رکھنے والا ایسا ہے جو ذی الحجہ کی دسویں رات کی صبح کے ساتھ خصوصیت رکھتا ہے اور وہ صبح خدا تعالیٰ کی قدرت یا اس کے دین کی صداقت کی شہادت دیتی ہے.اور پھر اس میں کیا حکمت تھی کہ صبح آئی تو دس راتوں کے بعد لیکن اس کا ذکر دس راتوں سے پہلے کر دیا گیا.اگر صرف دس راتوں کا ذکر ہوتا تو ہمیں ان کی بات تسلیم کرنے میں کوئی عذر نہیں تھا ہم سمجھتے کہ ان دس راتوں کا خدا تعالیٰ نے اس لئے ذکر کیا ہے کہ یہ راتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کے واقعہ کی طرف اشارہ کرتی ہیں.خدا تعالیٰ نے ان سے ایک وعدہ کیا تھا جسے اس نے پورا کیا اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کو زندگی بخشی اور اس کے ذریعہ ہمیشہ کے لئے دنیا میں ایک نشان قائم کر دیا یہ واقعہ میں ایک بڑا بھاری نشان تھا اور اس نے دنیا پر ثابت کر دیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں سے جو وعدے کیا کرتا ہے مخالف حالات کے باوجود وہ ان وعدوں کو پورا کرتا اور انہیں دنیا میں عزت اور کامیابی عطا کرتا ہے.ابراہیمؑ نے خدا تعالیٰ پر توکل کیا اور اس نے اپنے بیٹے کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے ماتحت ایک بے آب وگیاہ جنگل میں چھوڑ دیا.بظاہر
Page 174
اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ خطرہ میں تھا مگر اللہ تعالیٰ نے پیش از وقت بتا دیا کہ یہ قربانی ضائع نہیں جائے گی.مکہ مرجعِ خلائق بنے گا اور خدا تعالیٰ کے اس نشان کو قیامت تک یاد رکھا جائے گا.اگر اس واقعہ کی یادگار منائی جائے تو کوئی شبہ نہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ایک زبردست ثبوت کی یادگار ہو گی اور اگر یہ واقعہ دنیا کے سامنے پیش کیا جائے تو کوئی احمق ہی ہو گا جو اس کا انکار کرے اور کہے کہ اس سے خدا تعالیٰ کا جلال ظاہر نہیں ہوتا.پس اگر خالی لَیَالٍ عَشْرٍ کا ذکر ہوتا تو میرے لئے یہ بات حل شدہ تھی اور میں بغیر کسی جھجک کے کہہ سکتا تھا کہ ان سے مراد ذی الحجہ کی دس راتیں ہی ہیں کیونکہ یہ راتیں اس عظیم الشان قربانی کی طرف اشارہ کرتی ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے ماتحت کی لیکن مشکل یہ ہے کہ یہاں لَیَالٍ عَشْرٍ کے ساتھ وَالْفَجْرِ کا بھی ذکر کیا گیا ہے.اگر کہو کہ اس سے مراد کوئی اور فجر ہے تو پھر بتانا چاہیے کہ وہ کون سی فجر ہے اور اگر کہو کہ لَیَالٍ عَشْرٍ میں سے آخری رات کی فجر مراد ہے تو سوال یہ ہے کہ اس فجر میں کیا خصوصیت ہے کہ اس کا علیحدہ ذکر کیا گیا ہے اور پھر اس کا راتوں سے پہلے کیوں ذکر کیا گیا ہے.دس دنوں کی فضیلت تو سمجھ میں آ سکتی تھی کیونکہ انسان پہلے قربانی کا ارادہ کرتا ہے پھر اس ارادہ کے مطابق سامان مہیا کرتا ہے اور آخر وہ وقت آتا ہے جب وہ اس قربانی کو ادا کر دیتا ہے اس نقطۂ نگاہ کے ماتحت بجائے یوم النحر کے اگر ہم سب کے سب دنوں کو مبارک کہہ دیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں لیکن سوال یہ ہے کہ ان دس راتوں کی آخری فجر میں کون سی ایسی خاص بات پائی جاتی ہے جسے ہم کفار کے سامنے پیش کر سکیں اور ان سے منوا سکیں کہ یہ فجر بھی خدا تعالیٰ کی قدرتوں کا ایک زبردست نشان ہے مگر یہ بات نہ مفسرین نے بیان کی ہے اور نہ ہی میری سمجھ میں آتی ہے.لَیَالٍ عَشْرٍ میں تو یقیناً ایسا نشان ہے جسے بادلائل کفار کے سامنے پیش کیا جا سکتا ہے اور انہیں خدا تعالیٰ کی قدرت کا قائل کیا جا سکتا ہے مگر لَیَالٍ عَشْرٍ کے ساتھ فجر کا کوئی جوڑ نظر نہیں آتا.اسی طرح مفسرین نے لَیَالٍ عَشْرٍ کی تفسیر تو بیان کر دی مگریہ نہیں بیان کیا کہ ان کے ساتھ وہ کون سے شفع اور وتر ہیں جو ایک نشان کا کام دیتے ہیں اور جن کو اللہ تعالیٰ شہادت کے طور پر پیش کر رہا ہے.آخر شفع اور وتر میں کون سی ایسی دلیل ہے جس سے خدا تعالیٰ کی ہستی کا ثبوت ملتا ہے یا جسے کسی نشان کی شہادت کے طور پر لوگوں کے سامنے پیش کیا جا سکتا ہے.یہ کہنا کہ دو۲ دن پہلے چلے جاؤ یا تیسرے دن چلے جاؤ یہ ایک حکم تو ہے مگر نشان اور معجزہ تو نہیں یا اس سے خدا تعالیٰ کی کسی قدرت کا تو ثبوت نہیں ملتا اور محض حکم سے ایک کافر کیونکر سبق حاصل کر سکتا ہے یا کافر پر اس بات سے کیا حجت ہو سکتی ہے کہ ہم نے کہہ دیا ہے کہ چاہو تو دو دن ٹھہرو اور چاہو تو تین دن ٹھہرو.
Page 175
میں سمجھتا ہوں ایک بے وقوف سے بےوقوف کے سامنے بھی یہ بات بیان کی جائے تو وہ ہنس پڑے گا اور کہے گا کہ اس میں خدا تعالیٰ کی ہستی یا اس کی قدرت کا کیا ثبوت ہے.آپ ہی کہہ دیا کہ دو دن ٹھہر کر آ جاؤ اور آپ ہی کہہ دیا کہ اگر چاہو تو تین دن ٹھہر کر آ جاؤ.اس میں کون سی ایسی خاص بات ہے جس کی بنا پر قسم کھا کر اس کا ذکر کیا گیا ہے یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے معمولی طور پر شفع اور وتر کا ذکر نہیں کیا.بلکہ فرمایا ہے میں قسم کھاتا ہوں شفع کی اور میں قسم کھاتا ہوں وتر کی.جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی شفع ہے جو کفار پر حجت تمام کرتا ہے اور کوئی وتر بھی ہے جس سے الگ طور پر کفار پر حجت تمام ہوتی ہے یا شفع اور وتر دونوں مل کر حجت پوری کرتے ہیں مگر یہ تینوں باتیں ذوالحجہ کے کسی شفع یا وتر میں نہیں پائی جاتیں.پھر ایک اور اعتراض یہ پیدا ہوتا ہے کہ مفسرین جو معنے کرتے ہیں اور جن میں سے بعض رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی پہنچائے جاتے ہیں ان میں وتر کا پہلے ذکر آتا ہے اور شفع کا بعد میں.لیکن قرآن کریم میں شفع کا پہلے ذکر آتا ہے اور وتر کا بعد میں.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ کہ میں شفع کو شہادت کے طور پر پیش کرتا ہوں اور میں وتر کو بھی شہادت کے طور پر پیش کرتا ہوں.اور شفع کے معنے کئے گئے ہیں دسویں ذی الحجہ کے اور وتر کے معنے کئے گئے ہیں نویں ذی الحجہ کے.ہر شخص جانتا ہے کہ نو۹ پہلے ہوتا ہے اور دس۱۰ بعد میں ہوتا ہے یعنی وتر پہلے ہے اور شفع بعد میں.مگر قرآن نے شفع کا ذکر پہلے کیا ہے اور وتر کا ذکر بعد میں کیا ہے اگر تو وَالْوَتْرِ وَالشَّفْعِ ہوتا تو یہ بات بن جاتی کہ وتر سے نویں ذی الحجہ مراد ہے اور شفع سے دسویں ذی الحجہ.مگر قرآن کریم نے شفع کا پہلے اور وتر کا بعد میں ذکر کیا ہے اور اس جگہ کوئی ایسی وجہ بھی نہیں بتائی گئی جس کی بنا پر ہم اس ذکر کو آگے پیچھے کر سکیں اور کہہ سکیں کہ فلاں وجہ سے دسویں رات کا ذکر پہلے کیا گیا ہے اور نویں رات کا ذکر بعد میں کیا گیا ہے.بعض لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ وزن ملانے کے لئے ایسا کیا گیا ہے مگر ہم یہ تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں کہ قرآن کریم صرف وزن کی خاطر الفاظ کو آگے پیچھے کر دیتا ہے.اگر یہاں شفع اور وتر کا آگے پیچھے ذکر ہے تو ضرور اس کی وجہ ہونی چاہیے اور وہ دلیل دینی چاہیے جس کی بنا پر شفع کا پہلے اور وتر کے بعد میں ذکر کیا گیا ہے مگر ایسی کوئی دلیل مفسرین کی طرف سے پیش نہیں کی گئی.اس کے علاوہ یہ بھی سوال ہے کہ وَالَّیْلِ اِذَایَسْرِ سے کیا مراد ہے.اگر دس راتوں سے ذی الحجہ کی دس راتیں ہی مراد ہیں تو پھر یہ کون سی رات ہے جس کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ وہ چلی گئی.لیل سے مراد شام سے صبح تک کا وقت ہوتا ہے.جب لَیَالٍ عَشْرٍ میں ساری دس راتیں آ چکی تھیں تو یہ کون سی نئی رات ہے جس کے متعلق کہا گیا ہے کہ وہ چلی گئی یا کون سی نئی رات ہے جو آگئی.چلی گئی کہہ لو یا آگئی کہہ لو دونوں صورتوں میں سوال
Page 176
پیدا ہوتا ہے کہ یہ کون سی لیل ہے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے یا دس راتوں میں سے کس خاص رات کی طرف اس میں اشارہ کیا گیا ہے اور جب یہ دسوں راتوں میں سے ہی ایک رات تھی تو کیوں وَلَیَالٍ عَشْرٍ کے بعد شفع اور وتر کا ذکر کرکے اس رات کا ذکر کیا گیا ہے شفع اور وتر کو درمیان میں لا کر اسے ان دس راتوں سے جن کا یہ حصہ ہے الگ کیوں کر دیا گیا ہے؟ پھر سوال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے پہلے دس راتوں کا ذکر کیا تھا تو ان دس راتوں کے چلے جانے کا مضمون اس میں خود بخود آگیا تھا بلکہ فجر کا لفظ بھی آ چکا تھا جو ان راتوں کے گذر جانے کی طرف اشارہ کر رہا تھا اس قدر وضاحت کے بعد دوبارہ وَالَّیْلِ اِذَایَسْرِ کہنے کا کیا مطلب ہوا.اگر کہو کہ اس کے معنے رات کے جانے کے نہیں بلکہ آنے کے ہیں تو یہ اور بھی لطیفہ ہے کہ دس راتیں آئیں اور گذر بھی گئیں مگر ان کا ذکر مکمل کر چکنے کے بعد بلکہ ان کے بعد شفع اور وتر کے الفاظ کہہ کر ایام منٰی کا ذکر کر دینے کے بعد پھر ان دس میں سے پہلی رات کے آنے کا دوبارہ ذکر کرنا شروع کر دیا گیا.اگر اس پہلی رات کے آنے میں کوئی نشان تھا تو وہ تو دس راتوں کے ذکر میں بیان ہو چکا اور اگر دس راتوں میں کوئی نشان تھا تو شفع اور وتر کا ذکر شروع کر کے اس نشان کے بیان کو ختم کر دیا گیا پھر نئے سرے سے پہلی رات کے ذکر کے کیا معنے ہوئے اگر کہا جائے کہ وہی فجر کا مضمون اس جگہ دہرایا گیا ہے تو یہ بھی بتانا چاہیے کہ وَالْفَجْرِ میں کون سی کمی رہ گئی تھی جسے وَالَّیْلِ اِذَایَسْرِ میں بیان کیا گیا ہے.پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس سے ذی الحجہ کی پہلی رات مراد ہے تو پہلی رات کی فجر کیا ثابت کرتی ہے؟ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اس سے آخری رات کی فجر مراد ہے لیکن ہمیں اس سے بحث نہیں پہلی رات کی فجر مراد ہو یا آخری رات کی.سوال یہ ہے کہ اس رات کی خصوصیت کیا ہے جس کی وجہ سے اس کا علیحدہ ذکر کیا گیا ہے اور ذوالحجہ کی پہلی یا آخری رات کی فجر میں کون سی ایسی بات پائی جاتی ہے جس سے کفار پر حجت تمام ہو سکتی ہے یا اللہ تعالیٰ کی قدرت ان پر ظاہر ہو سکتی ہے؟ جب قسم شہادت کے لئے ہوتی ہے تو پہلی رات یا آخری رات کی فجر کس امر کی شہادت دیتی ہے اور دس راتیں کس امر کی شہادت دیتی ہیں؟ میںبتا چکا ہوں کہ اگر حج کی وجہ سے ان راتوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سچائی کا ثبوت قرار دیا جائے تو یہ ایک معقول بات ہو گی مگر پھر یہی سوال پیدا ہو گا کہ یہ تو مان لیا کہ یہ راتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صداقت کا ثبوت ہیں مگر پہلی رات کی فجر کس امر کا ثبوت دیتی ہے اور پھر آخری رات کسی خاص امر کی شہادت دیتی ہے یا کس مضمون کو مکمل کرتی ہے؟ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ کسی کُل کے ذکر پر اس کے ہر ٹکڑے کا مستقل طور پر الگ الگ شہادت دینا ضروری نہیں مگر جب کُل کے ذکر کے بعد یا پہلے
Page 177
بعض ٹکڑوں کا الگ ذکر کیا جائے تو پھر لازمًا ان ٹکڑوں کے ذکر سے کوئی مزید شہادت کا حاصل ہونا ضروری ہو گا.لیکن وَالَّیْلِ اِذَایَسْرِ کی کوئی خاص شہادت ان مفسرین نے بیان نہیں کی.اگر یہ کہا جائے کہ یہ چاروں مضمون الگ الگ شہادت نہیں رکھتے بلکہ مل کر ایک شہادت بنتے ہیں تو ہم اس کو بھی ماننے کے لئے تیار ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ حج کے ساتھ فجر اور شفع اور وتر اور وَالَّیْلِ اِذَایَسْرِ مل کر کیا شہادت پیدا کرتے ہیں.اگر لَیَالٍ عَشْرٍ کے ساتھ فجر کو نہ ملایا جاتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے پورا ہونے میں کیا کمی رہ جاتی.اگر شفع اور وتر کا ذکر نہ کیا جاتا تو کون سا امر مخفی رہ جاتا یا وَالَّیْلِ اِذَایَسْرِ کا ذکر اگر نہ ہوتا تو دس راتوں کی شہادت اور ان کے معجزہ میں کون سا نقص رہ جاتا؟ ہم مانتے ہیں کہ بعض دفعہ دلیل کو نمایاں کرنے کے لئے اس کے مختلف حصے کر دیئے جاتے ہیں مگر ایسا تبھی کیا جاتا ہے جب ان مختلف حصوں پر زیادہ زور دے کر دلیل کو نمایاں اور روشن کرنا مقصود ہو.بلاوجہ ایک دلیل کے مختلف حصے نہیں کئے جاتے.اگر فجر اور شفع اور وتر اور وَالَّیْلِ اِذَایَسْرِ کے مفہوم میں لَیَالٍ عَشْرٍ کی بعض خصوصیات کا ذکر کیا جاتا تو ہمیں اس کو تسلیم کرنے میں کوئی عذر نہ ہوتا.ہم سمجھتے کہ گو فجر اور شفع اور وتر اور وَالَّیْلِ اِذَایَسْرِ کا دس راتوں سے جن کا وہ حصہ ہیں علیحدہ طور پر بھی ذکر کیا گیا ہے مگر اس ذکر کی غرض ان امور کی اہمیت کی طرف اشارہ کرنا ہے اور ان پر زور دینے کے لئے الگ بیان کیا گیا ہے ورنہ اصولًا یہ تمام حصے دس راتوں میں ہی شامل ہیں اور ہر حصہ اس دلیل کا ایک مفید اور ضروری حصہ ہے مگر افسوس تو یہ ہے کہ مفسرین کی طرف سے لَیَالٍ عَشْرٍ کے جو معنے کئے جاتے ہیں ان میں نہ فجر کا ذکر دلیل کا کوئی حصہ بنتا ہے نہ شفع اور وتر کا ذکر کوئی معنے رکھتا ہے اور نہ وَالَّیْلِ اِذَایَسْرِ کا کوئی مفہوم ثابت ہوتا ہے گویا ایسے معنے کئے جاتے ہیں جو کسی صورت میں بھی آیاتِ قرآنیہ سے مطابقت نہیں رکھتے.دوسری تو جیہ محرم کی راتوں کی ہے.اس میں بھی اگر تو صرف اتنا ہوتا کہ وَالْفَجْرِ وَلَیَالٍ عَشْرٍ تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ توجیہ چسپاں ہو جاتی اور ہمیں اس تفسیر کو درست تسلیم کرنا پڑتا کیونکہ حدیثوں میں آتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ وہ دن ہیں جن میںحضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون پر غلبہ ملا اور سمندر سے نجات حاصل ہوئی.اور اسی طرح کا ایک واقعہ میری اُمت میں بھی آئندہ زمانہ میں ہو گا (ترمذی ابواب الصوم)پس جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ ذی الحجہ کی دس راتوں پر چسپاں ہو سکتا ہے اسی طرح اگر وَالْفَجْرِ وَلَیَالٍ عَشْرٍ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس عظیم الشان واقعہ کی طرف اشارہ سمجھا جائے تو کوئی بڑے سے بڑا معترض بھی اس
Page 178
کی عظمت اور اہمیت سے انکار نہیں کر سکتا.اس صورت میں وَالْفَجْرِ سے محرم کی دسویں رات کی صبح مراد لے لی جائے گی اور لَیَالٍ عَشْرٍ سے محرم کی ابتدائی دس راتیں.کیونکہ ان دس راتوں میں سے کچھ وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون سے بحث کرنے میں گذرا ہو گا.کچھ وقت سامانِ سفر کو درست کرنے میں صرف ہوا ہو گا اور اس لحاظ سے ان تمام راتوں کو ہی خدا تعالیٰ کا ایک نشان قرار دینا پڑے گا.بہرحال اگر صرف وَالْفَجْرِ وَلَیَالٍ عَشْرٍ تک ہی آیت ہوتی تو ہم تسلیم کر لیتے کہ فجر سے مراد وہ فجر ہے جب حضرت موسٰی علیہ السلام مصر سے بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر نکلے اور فرعون سمندر میں غرق ہوا.اور لَیَالٍ عَشْرٍ سے مراد محرم کی ابتدائی دس راتیں ہیں کیونکہ وہ سب کی سب خدا تعالیٰ کے اس نشان کی مظہر ہیں کہ بنی اسرائیل نے موسٰی کی پیروی میں فرعون کے مظالم سے نجات حاصل کی.مگر اس موقع پر بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ کا اس واقعہ سے کیا جوڑ ہوا یہ بالکل تشنہء تفسیر رہ جاتا ہے.اسی طرح یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر حضرت موسٰی علیہ السلام کے واقعہ کی طرف اس میں اشارہ ہے تو وَالَّیْلِ اِذَایَسْرِ کے کیا معنے ہوئے اور محرم کی دس راتوں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ سے اس رات کا جوڑ کیا ہے؟ اگر صرف فجر اور دس راتوں کا ذکر ہوتا تو عقلی طور پر ہمیں اس توجیہ کو تسلیم کرنے میں ہرگز کوئی عذر نہیں تھا جس طرح عقلی طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کے واقعہ پر ذوالحجہ کی دس راتیں یا یوم النحر کی فجر چسپاں ہو سکتی ہے اسی طرح عقلی طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ بھی چسپاں ہوسکتا ہے.پس اگر صرف اتنی ہی آیت ہوتی تو کوئی شخص اس واقعہ کی اہمیت کا انکار نہیں کر سکتا تھا بلکہ ہر شخص کے نزدیک یہ شہادت ایک اہم شہادت ہوتی.ایک اہم قسم ہوتی اور عرفان بخش قسم ہوتی مگر اگلی دو آیتیں ہمیں اس طرف بھی جانے نہیں دیتیں.تیسری توجیہ رمضان کی دس راتوں کی ہے اس میں اوّل تو اختلاف ہے.بعض روایات میں پہلی دس اور بعض میں آخری دس راتوں کو ان کا مصداق قرار دیا گیا ہے مگر پہلی ہوں یا پچھلی سوال یہ ہے کہ رمضان کی راتیں کس امر کی شہادت دیتی ہیں.یہ سورۃ ابتدائی سالوں کی ہے اور اس پر قریباً سب کا جو کوئی رائے رکھ سکتے ہیں اتفاق ہے لیکن رمضان کے روزے فرض ہوتے ہیں مدینہ میں.جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے ہیں تو اس وقت تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے دوسرا ماہ رمضان جو مدینہ میں آیا اس وقت یہ روزے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہوئے (طبری زیر عنوان السنۃ الثانیۃ من الھجرۃ) اب بتاؤ کہ کیا کوئی بھی معقول انسان اس توجیہ کو مان سکتا ہے خواہ زمانۂ حال کا کوئی مفسر ہو یا ماضی کا مجھے بتائے کہ کیا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہستی اور اس کی قدرت کی کوئی دلیل ہے کہ لوگوں سے کہا جائے ہم صداقت کے ثبوت کے طور پر یہ بات پیش
Page 179
کرتے ہیں کہ آج سے بارہ سال کے بعد ہم اپنے ساتھیوں سے کہیں گے کہ وہ رمضان کے روزے رکھا کریں.روزہ رکھنے کا حکم دینا تو انسان کے اپنے اختیار کی بات ہے ایک مفتری بھی اگر چاہے تو ایسا حکم اپنے ماننے والوں کو دے سکتا ہے.مسیلمہ کذاب بھی ایک جھوٹی شریعت بنا سکتا تھا.دیکھنا تو یہ ہے کہ آیا جو بات پیش کی جا رہی ہے وہ کافروں کے لئے بھی حجت ہے یا نہیں؟ پھر عجیب بات ہے کہ اس توجیہ کو درست تسلیم کرنے کی صورت میں کفار کے سامنے حجت کے طور پر رمضان کی راتوں کو پیش کیا گیا ہے مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت تھی کہ آپ ان دنوں محرم کے پہلے دس دنوں کے روزے رکھا کرتے تھے کیونکہ ان ایام میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی.چونکہ اس واقعہ کی یادگار کے طور پر یہودی لوگ یہ روزے رکھا کرتے تھے اس لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم بھی یہ روزے رکھتے تھے.جب رمضان کے روزوں کے احکام نازل ہو گئے تو آپ نے یہ روزے چھوڑ دیئے.پس سوال یہ ہے کہ جو روزے ابھی فرض ہی نہیں ہوئے تھے اور جن کو نہ مسلمان جانتے تھے اور نہ کفار جانتے تھے ان کے ذکر سے مسلمانوں نے کیا سمجھا.یا کافروں نے کیا سمجھا ہو گا.جب یہ روزے سورۃ الفجر کے نزول کے وقت فرض ہی نہیں تھے تو ان کی شہادت کیا اثر رکھ سکتی تھی اور ان سے کفار پر کیا حجت ہو سکتی تھی.ممکن ہے کہ کوئی شخص کہہ دے کہ بے شک رمضان کے روزے بارہ سال بعد مدینہ منورہ میں جا کر فرض ہوئے ہیں مگر ان کا قبل ازوقت ذکر کرنا یا رمضان کی راتوں کی قسم کھانا قابل اعتراض امر نہیں.قرآن کریم نے خود متعدد مقامات پر آئندہ زمانوں میں ہونے والے واقعات کی قسم کھائی ہے مثلاً قرآن کریم نے یہ کہا ہے یا نہیں کہ اِذَاالشَّمْسُ کُوِّرَتْ(التکویر:۲).ایک زمانہ آئے گا جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت کو ترک کر دیا جائے گا یا انوارِمحمدیہ کا نزول بند ہو جائے گا یا سورج اور چاند کو گرہن لگے گا.پھر کیا یہ واقعات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی رونما ہو گئے تھے؟ ہر شخص جانتا ہے کہ یہ پیشگوئیاں بعد میں پوری ہوئیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان بعد میں رونما ہونے والے واقعات کی خود قسم کھائی ہے.اسی طرح وَاِذَا النُّفُوْسُ زُوِّجَتْ(التکویر:۸) میں یہ پیشگوئی کی گئی تھی کہ ایک زمانہ میں ریل تار اور ریڈیو وغیرہ سے باہمی تعلقات ایسے ہو جائیں گے کہ گویا پاس بیٹھے ہیں.مگر یہ پیشگوئیاں ایک لمبا عرصہ گذرنے کے بعد پوری ہوئیں.اسی طرح خواہ رمضان کے روزے بارہ سال بعد فرض ہوئے مگر اِذَاالشَّمْسُ کُوِّرَتْ اور اِذَاالنُّفُوْسُ زُوِّجَتْ اور اسی قسم کی اور متعدد پیشگوئیوں کی طرح رمضان کی راتوں کی بھی قسم کھائی جا سکتی تھی.
Page 180
اس سوال کے متعلق یہ یاد رکھنا چاہیے کہ بے شک آئندہ امور کی قسم قرآن کریم میں موجود ہے مگر وہ تمام واقعات ایسے ہیں جن سے علمِ غیب وابستہ تھا.درحقیقت وہ پیشگوئیاں ہیں جو آئندہ زمانہ کے متعلق کی گئی تھیں اور پیشگوئی ایسی چیز ہے جو بندے کے اختیار میں نہیں ہوتی.لیکن ایک پیر کا اپنے مرید کو کوئی حکم دے دینا اس کے اپنے اختیار کی بات ہے اور اس میں ہر گز علمِ غیب کا کوئی حصہ نہیں.مثلاً تحریک جدید کا ہماری جماعت میں ۱۹۳۴ء سے آغاز ہوا ہے اگر میں اس تحریک کو شروع کرنے سے دو سال پہلے اعلان کر دیتا کہ ۱۹۳۴ء میں مَیں تحریک جدید جاری کروں گا اور جب ۱۹۳۴ء آتا تو تحریک جدید کو جاری کر کے کہتا کہ دیکھو یہ خدا تعالیٰ کا کتنا بڑا نشان ہے میں نے دو سال پہلے جو بات کہی تھی وہ پوری ہو گئی.تو ہر شخص ہنسنے لگ جاتا کہ اس میں نشان کی کون سی بات ہے.یہ تو اپنے اختیار کی چیز تھی کہ جب چاہا اپنے مریدوں کو حکم دے دیا اور جب چاہا نہ دیا.یا مثلاً میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ فلاں وقت میں سات روزے رکھنے کے متعلق اعلان کر وں گا اور جب بھی وہ وقت آیا میں نے روزوں کے متعلق جماعت میں اعلان کر دیا.اب کیا میرا قبل از وقت یہ کہنا کہ میں فلاں مہینہ میں روزے رکھنے کا حکم دوں گا اور پھر اس مہینہ کے آنے پر روزوں کا اعلان کر دینا اپنے اندر کوئی نشان رکھتا ہے کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ ایک معجزہ ہے جو ظاہر ہوا یا یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس سے خدا کی ہستی کا ثبوت ملتا ہے.اسی طرح اگر رمضان کے روزوں کے متعلق کہہ دیا گیا تھا تو اس میں کون سی ایسی بات ہو گئی جس سے کافروں پر حجت تمام کی جا سکتی ہے.یہ تو ہمارا ایمان ہے کہ قرآن کریم میں جو کچھ لکھا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے مگر کافر تو اس بات کو نہیں مانتا وہ تو کہتا ہے کہ یہ سب باتیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم نے خود اپنی طرف سے بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کی ہیں اور جب کہ کفار قرآن کریم کو خدا تعالیٰ کا کلام مانتے ہی نہیں تو ان کے سامنے یہ بات بطور حجت کس طرح پیش کی جاسکتی ہے کہ بارہ سال بعد رمضان کے روزے فرض کئے جائیں گے اور اس کی دس راتیں بڑی اہمیت رکھیں گی.ایک مخالف کہہ سکتا ہے کہ خود ہی بارہ سال پہلے ایک سکیم پیش کر دی گئی اور پھر خود ہی اس کے مطابق اعلان کر کے کہہ دیا کہ یہ خدا کا نشان ظاہر ہو گیا ہے.اس میںنشان کی کون سی بات ہے ایسا تو ہر شخص کر سکتا ہے.پس یہ بالکل غلط ہے کہ جس رنگ میں قرآن کریم نے آئندہ زمانہ میں رونما ہونے والے واقعات کی قسم کھائی ہے اسی رنگ میںرمضان کی راتوں کی قسم سمجھی جا سکتی ہے.رمضان کے روزوں کا حکم دینا بندے کا اختیاری فعل ہے چند سال پہلے ہی اپنی کسی سکیم کا اعلان کر دینا اپنے اندر کوئی نشان نہیں رکھتا لیکن آئندہ زمانوں میں رونما ہونے والے واقعات کی خبر دینا جو انسان کے اختیار میں نہ ہوں یہ کام یقیناً کسی انسان کا نہیں ہو سکتا.قرآن کریم
Page 181
میں جہاں جہاں بھی قسم کھائی گئی ہے وہاں ایسے ہی واقعات کے متعلق قسم کھائی گئی ہے جو آئندہ زمانوں میں رونما ہونے والے تھے اور جن پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کی اُمت کو نہ کوئی اختیار حاصل تھانہ اختیار حاصل ہونا ممکن ہو سکتا تھا اور جو خدا تعالیٰ کی ہستی اور اس کی قدرت اور اس کے علم کا ایک زبردست نشان تھے مثلاً یہ کہا گیا کہ اِذَاالشَّمْسُ کُوِّرَتْ.ایک زمانہ آئے گا جب سورج اور چاند کو گرہن لگے گا.اب بتاؤ کہ کیا سورج اور چاند کو گرہن لگانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت میں تھا؟یا اِذَاالنُّفُوْسُ زُوِّجَتْ میں جب ریل اور تار اور ڈاک کی ایجاد کی خبر دی گئی تھی تو کیا ان چیزوں کی ایجاد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم کے اختیار میں تھی؟ ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ یہ خبریں ایسی تھیں جن کو پورا کرنا کسی انسانی طاقت کا کام نہیں تھا بلکہ اللہ تعالیٰ ہی ان کو پورا کر سکتا تھا اسی لئے ان واقعات کو اللہ تعالیٰ کی ہستی کے ثبوت کے طور پر پیش کیا گیا ہے.غرض قسمیں انہی امور کے متعلق کھائی جاتی ہیں جو مستقبل سے تعلق رکھنے والے ہوں یا ہوں تو زمانۂ ماضی کے مگر ان سے اللہ تعالیٰ کی طاقت اور اس کی قدرت کا اظہار ہوتا ہو.زمانۂ حال کے ایک مفسر نے لکھا ہے کہ رمضان کی آخری دس راتوں کو بطور شہادت اس لئے پیش کیا گیا ہے کہ ان میں روزے رکھ کر انسان کے تقویٰ اور اس کی روحانیت میں خاص طور پر ترقی ہوتی ہے(بیان القرآن مولوی محمدعلی صاحب سورۃ الفجر).مگر سوال یہ ہے کہ کیا کافر بھی یہ مانتا ہے کہ روزہ سے تقویٰ بڑھتا ہے یا روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے ؟ وہ دس روزوں کا ہی نہیں بلکہ سارے روزوں کا بھی یہ نتیجہ تسلیم نہیں کرتا.سارے کیا اگر کوئی شخص پچاس سال بھی متواتر روزے رکھتا چلا جائے تو وہ یہ تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں کہ ان روزوں سے اس کی روحانیت میں اضافہ ہوا ہو گا.پس جس بات کو وہ مانتا ہی نہیں اسے بطور شہادت اس کے سامنے کس طرح پیش کیا جاسکتا ہے؟وہ تو یہی کہے گا کہ یہ بالکل جھوٹ ہے روزوں سے روحانیت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا.پس قسمیں انہی واقعات کے متعلق کھائی جا سکتی ہیں جو مستقبل سے تعلق رکھتے ہوں اور جن سے اللہ تعالیٰ کی ایسی قدرت کا اظہار ہوتا ہو جو دشمنانِ دین کے لئے حجت ہو سکے اور یا پھر ان واقعات پر قسمیں کھائی جاتی ہیں جو گو زمانۂ ماضی سے تعلق رکھتے ہوں مگر اللہ تعالیٰ کی ہستی اور اس کی قدرت کا نشان ان سے ظاہر ہو چکا ہو.مثلاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی.آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے وعدے اور اللہ تعالیٰ کا ان وعدوں کو پورا کرنا یہ سب زمانۂ ماضی سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں مگر چونکہ تاریخی طور پر یہ باتیں ثابت ہیں دشمن ان کا انکار نہیں کر سکتا.اس لئے انہیں دشمن کے سامنے بطور حجت پیش کیا جا سکتا ہے لیکن روحانی ترقی تو ایک ایسی چیز ہے جو دوست کو بھی نظر نہیں آتی کجا یہ
Page 182
کہ اسے دشمن کے سامنے پیش کیا جائے.پس یہ بات یہاں چسپاں ہی نہیں ہو سکتی کہ جس طرح آئندہ زمانہ میں ہونے والے واقعات کی قرآن کریم نے قسم کھائی ہے اسی طرح رمضان کی کھائی ہے قرآن کریم میں قسم ان واقعات کی کھائی گئی ہے جن سے علم غیب وابستہ تھا مثلاً سورج گرہن، عوام کی بیداری، بادشاہتوں کی تباہی، ان امور کے متعلق قبل ازوقت خبر یقیناً خدا تعالیٰ کی قدرت کا ایک زبردست ثبوت ہے مگر رمضان کے روزے تو علمِ غیب اپنے اندر نہیں رکھتے ہر شخص اپنی جماعت کو ایک حکم دے سکتا ہے اور ایسا حکم اس کی سچائی کا ثبوت نہیں ہوسکتا.کفار کے نزدیک وہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل تھا اور عبادت کے طور پر اس کی خبر مکہ والوں کو پہلے دینے میں کوئی فائدہ نہیں تھا.غرض خدا تعالیٰ کی قدرت اور اس کے نشان کے طور پر وہی بات پیش کی جا سکتی ہے جو علمِ غیب اپنے اندر رکھتی ہو.جیسے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے زلزلۃ الساعۃ کی خبر دی(تذکرۃصفحہ ۴۵۰).اب یہ ایسی خبر ہے جس کو پورا کرنا کسی انسان کے اختیار کی بات نہیں.اس خبر کو اگر خدا تعالیٰ کی ہستی اور اس کی قدرت کا ثبوت قرار دیا جائے تو یہ بالکل درست ہو گا.لیکن احکام کی قسم کھانے سے اس کی قدرت کا کچھ بھی اظہار نہیں ہوتا پس رمضان کی راتوں کی قسم چونکہ اپنے اندر کوئی علمِ غیب یا ایسا اظہارِ قدرت اپنے اندر نہیں رکھتی جیسے کہ مثلاً وَالتِّیْنِ وَالزَّیْتُوْنِ.وَطُوْرِ سِیْنِیْنَ(التین:۲،۳) کی قسمیں رکھتی ہیں کہ ہیں تو ماضی کے امور.آئندہ کا علم غیب ان میں نہیں مگر ماضی کے علمِ غیب کے ظہور کا ثبوت ان میں موجود ہے جس کا دشمن انکار نہیں کر سکتا.یا مثلاً اِذَاالشَّمْسُ کُوِّرَتْ.وَاِذَاالنُّجُوْمُ انْکَدَرَتْ.وَاِذَا الْجِبَالُ سُیِّرَتْ.وغیرہ پیشگوئیاں ہیں کہ یہ سب کی سب اپنے اندر علمِ غیب رکھتی ہیں اور خدا تعالیٰ کی قدرت کا ثبوت ہیں اس لئے وہ قسم فضول ہے اور قرآن کریم ایسی فضول قسموں سے بالا ہے.غرض لَیَالٍ عَشْرٍ میں واقعہ ابراہیمی کی طرف اشارہ یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نجات کی طرف تو ایک معقول بات بن سکتی ہے.لیکن رمضان کی پہلی یا پچھلی راتوں کا ذکر ان آیات سے نکالنا اپنے اندر کوئی حکمت کی بات نہیں رکھتا.غیب کی خبریں خواہ ماضی میں پوری ہو چکی ہوں یا آئندہ پیدا ہونے والی ہوں بے شک ایمان افزا ہوتی ہیں مثلاً خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ میں تجھے اور بنی اسرائیل کو فرعون پر غلبہ دوں گا (خروج باب ۷ آیت ۱تا۷) اور پھر خدا تعالیٰ نے اپنے اس وعدہ کو پورا کر کے فرعون کو غرق کر دیا اور بنی اسرائیل کو اس کے مظالم سے نجات دی.اب گو یہ زمانۂ ماضی کا ایک واقعہ ہے مگر تاریخ میں یہ واقعہ محفوظ ہے اور اسے دشمن
Page 183
کے سامنے بطور حجت پیش کیا جا سکتا ہے.آج بھی جب یہ واقعہ کسی کے سامنے بیان کیا جائے گا خدا تعالیٰ کی ہستی کا ایک زندہ ثبوت اسے نظر آنے لگ جائے گا.بے شک حضرت موسیٰ فوت ہو گئے فلسطین پر جو حکومت قابض تھی وہ جاتی رہی.مگر باوجود اس کے آج بھی جب کسی ہندو یا سکھ کے سامنے ان واقعات کو پیش کیا جائے وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا.وہ کہے گا خواہ موسٰی مر گئے.فلسطین سے یہود کی حکومت مٹ گئی مگر اس کے باوجود یہ ایک ثابت شدہ حقیقت ہے اور تاریخ اس کی سچائی پر شاہد ہے کہ موسٰی نہایت ادنیٰ اور کمزور حالت میں تھے.بنی اسرائیل کی فرعون کے مقابلہ میں کوئی حیثیت ہی نہیں تھی وہ جس طرح چاہتا ان سے سلوک کرتا.ایسی کمزور اور ذلیل حالت میں اللہ تعالیٰ نے موسٰی سے وعدہ کیا کہ میں تجھے کامیاب کروں گا.واقعات ان کی کامیابی کے خلاف تھے مگر خدا نے اپنے وعدہ کو پورا کیا.فرعون اپنی ساری طاقت اور اپنے سارے لشکر اور اپنے سارے سازوسامان کے باوجود ناکام ہوا.ناکام و نامراد ہونے کی حالت میں مرا اور موسٰی اپنے ساتھیوں سمیت خدا تعالیٰ کے وعدہ کے مطابق کامیاب ہو گیا.یہ واقعہ خواہ ماضی کا ہے مگر تاریخی شہادت اس ماضی کو ایسا شاندار بنا دیتی ہے کہ آج بھی اس واقعہ کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نقشہ انسانی آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے.اسی طرح ابراہیمؑ فوت ہو چکے جو پیشگوئیاں انہوں نے کی تھیں وہ قصۂ ماضی بن چکیں مگر اس کے باوجود اس ماضی کا بھی ایک ماضی تاریخ میں محفوظ ہے جب ہم اس گذشتہ ماضی میں جا کر اس واقعہ کو مستقبل کی نظر سے دیکھتے ہیں تو ہمیں خدا تعالیٰ کا یہ ایک حیرت انگیز اور عجیب نشان نظر آتا ہے ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو زمانۂ حاضر میں کھڑے ہو کر نہیں دیکھتے بلکہ ابراہیم ؑ کے وقت کی تاریخ میں دیکھتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ کیا اس قسم کی پیشگوئی کرنا ابراہیمؑ کے لئے ممکن تھا اس وقت جب ہم تاریخ کی نلکی میں سے جھانکتے ہوئے ابراہیمؑ کے زمانہ تک پہنچتے ہیں.جب ہم ماضی سے مستقبل کی طرف نگاہ دوڑاتے ہیں توہمیں یہ ایک زبردست پیشگوئی نظر آتی ہے اور ہمارا دل اس یقین سے پُر ہو جاتا ہے کہ یہ خدا کا ایک زندہ نشان ہے جو ابراہیم کے ذریعہ ظاہر ہوا.تو بعض ماضی بھی خدا تعالیٰ کی قدرت کا ثبوت ہوتے ہیں کیونکہ اس ماضی کا بھی ایک ماضی تھا جب ہم گذشتہ ماضی میں کھڑے ہو کر مستقبل کو دیکھتے ہیں تو یہ ماضی ہمارے لئے ایک نشان بن جاتا ہے اور مستقبل تو ظاہر ہی ہے.جب ایک پیشگوئی پوری ہو جاتی ہے تو وہ ایک زندہ ثبوت ہوتی ہے خدا تعالیٰ کی ہستی اور اس کی قدرت اور اس کے جلال اور اس کی عظمت کا.مگر رمضان کے روزوں کی جو ابھی نازل نہیں ہوئے تھے قسم کھانے سے ان فوائد میں سے جو قرآنی قسموں میں ہیں ایک فائدہ بھی پایا نہیں جاتا.اس اصولی سوال کو نظرانداز کر دو تو پھر بھی سوال ہے کہ رمضان کی پہلی راتوں میں سے فجر کس امر کی شہادت
Page 184
دیتی ہے کہ اسے الگ کر کے بیان کیا ہے؟ پھر اس میں شفع اور وتر کا کیا سوال ہے کہ ان کا ذکر کیا گیا ہے؟ پھر وہ کون سی رات ہے جسے اِذَایَسْرِ کہا گیا ہے اور اس رات سے کیا شہادت نکلتی ہے؟ اور اگر آخری راتیں مراد ہیں پھر اَلْفَجْرِ سے کیا مراد ہے یعنی اگر پہلی دس راتیں مراد ہیں تو اَلْفَجْرِ سے کیا مراد ہے اور اگر آخری دس راتیں مراد ہے تو اَلْفَجْرِ سے کیا مراد ہے؟ اور اَلْفَجْرِ میں پہلی راتوں کی کسی فجر کا ذکر ہے یا آخری راتوں کی کسی فجر کا ذکر کیا ہے؟ آخری یا پہلی راتیں مراد لینا تو پھر بھی ایک معقول بات ہے.کیونکہ پہلی راتیں رمضان کے شروع کی ہیں اور دوسری راتیں رمضان کے اختتام کی.ایک کی یہ عظمت بیان کی جا سکتی ہے کہ ان سے رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہوتا ہے اور دوسری راتوں کی یہ عظمت بیان کی جا سکتی ہے کہ ان پر رمضان کا اختتام ہوتا ہے اور اس وجہ سے وہ خاص اہمیت رکھتی ہیں.مگر سوال یہ ہے کہ ان راتوں کی کون سی فجر ایسی خصوصیت رکھتی ہے کہ اس کی قسم کھائی گئی ہے اور جس سے دشمن پر حجت تمام کی جا سکتی ہے اور اسے خدا تعالیٰ کی قدرت کا قائل کیا جا سکتا ہے.بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس جگہ فجر سے لیلۃ القدر کی فجر مراد ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هِيَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ(القدر:۶) لیلۃ القدر مطلعِ فجر تک ہوتی ہے(بیان القرآن مولوی محمد علی صاحب سورۃ الفجر).مگر سوال یہ ہے کہ لیلۃ القدر مبارک ہوتی ہے نہ کہ اس کی فجر.فجر کو تو وہ برکات ختم ہو جاتی ہیں پھر اس وقت کی قسم کیوں کھائی گئی ہے؟ کیا یہ تعجب کی بات نہیں کہ جو مبارک چیز تھی یعنی لیلۃ القدر اس کا تو ذکر ہی نہیں کیا اور جس میں کوئی خاص بات نہ تھی یعنی فجر اسے بیان کر دیا.حالانکہ اس سے کسی خاص مبارک وقت کی طرف اشارہ پایا ہی نہیں جاتا.پھر سوال یہ ہے کہ ان دس راتوں میں سے وتر کس امر کی طرف اشارہ کرتا ہے اور شفع کس امر کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ وتر سے مراد یہاں لیلۃ القدر ہے کیونکہ لیلۃ القدر وتر رات میں آتی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ یہاں وتر کے ساتھ شفع کابھی ذکر آتا ہے.یہاں صرف یہ نہیں کہا گیا کہ ہم ایک وتر کو شہادت کے طور پیش کرتے ہیں بلکہ وتر اور شفع دونوں کو اکٹھا بطور شہادت پیش کیا گیا ہے اگر وتر سے مراد رمضان کے آخری عشرہ کی وتر راتیں مراد ہیں اور شفع سے مراد آخری عشرہ کی جفت راتیں.تو شفع کے لحاظ سے پانچ راتیں مبارک ہوں گی اور وتر کے لحاظ سے بھی پانچ مبارک ہوں گی یا کبھی دس کی بجائے صرف نو راتیں بھی ہو سکتی ہیں.بہرحال جب دس راتوں میں سے پانچ شفع اور پانچ وتر ہیں یا چار شفع اور پانچ وتر ہیں.تو یا تو شفع اور وتر سے ساری راتیں مراد ہوں گی اور یا پھر ان میں سے کوئی ایک وتر اور ایک شفع مراد ہو گی.اگر یہ کہا جائے کہ وتر سے مراد صرف ایک وتر رات مراد ہے جو لیلۃ القدر ہوتی ہے تو شفع سے مراد بھی کوئی ایک ایسی جفت رات ہونی چاہیے جو خاص حیثیت رکھنے والی ہو مگر شفع کے معنے
Page 185
کرتے وقت تو ان پانچوں راتوں کو لے لینا جو جفت ہوں یا چار راتوں کو لے لینا جو جفت ہوں اور وتر سے مراد صرف ایک رات لینا یہ کوئی معقول بات نہیں ہے.پھر یہ سوال بھی ہے کہ لیلۃ القدر تو وتر راتوںمیں سے ایک ہے لیکن وتر راتیں تو دس راتوں میں کئی آتی ہیں ان کی قسم کیوں کھائی ہے یا کس قرینہ سے لیلۃ القدر کے سوا دوسری وتر راتوں کو خارج سمجھا جائے اور پھر شفع کی قسم کی کیا وجہ ہے اگر شفع بھی مبارک ہیں اور وتر بھی تو الگ بیان کرنے کی وجہ کیا تھی؟ لَیَالٍ عَشْرٍ میں ان ساری راتوں کا ذکر آ چکا تھا.آخرشفع اور وتر سے یہی مراد لیا جائے گا کہ پانچ طاق راتیں اور پانچ جفت راتیں.مگر سوال یہ ہے کہ یہ ذکر تو لَیَالٍ عَشْرٍ میں پہلے ہی آ چکا ہے شفع اور وتر کے ساتھ جفت اور طاق راتوں کا الگ الگ ذکر کیوں کیا گیا ہے جب اللہ تعالیٰ نے دس راتوں کی قسم کھا لی تھی تو ان میں وتر راتیں بھی آ گئی تھیں اور جفت بھی ان کا ذکر علیحدہ کرنے کاکوئی فائدہ نہ تھا.پھر سب سے آخر میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ وَالَّیْلِ اِذَایَسْرِ کیا شے ہے لَیَالٍ عَشْرٍ میں تو دس راتیں سب آ گئی تھیں جو دراصل نو ہوتی ہیں دس ہوتی ہی نہیں لیکن یہاں ایک گیارھویں رات کا بھی ذکر ہے.اگر اعتکاف مراد لو تو اس کی بھی گیارہ راتیں کسی صورت میں نہیں ہوتیں یا دس بنیں گی یا نو۹.ہاں بعض دفعہ گیارہ دن ہو جاتے ہیں.غرض کوئی معنے آیاتِ قرآنیہ سے مطابقت نہیں کھاتے اور ہر ایک پر متعدد اور شدید اعتراضات وارد ہوتے ہیں.سورۂ فجر کی پہلی چار آیات کی خدا تعالیٰ کی بتائی ہوئی تفسیر اب میں اپنے معانی بیان کرتا ہوں جو مجھے اللہ تعالیٰ نے یک دم سجدۂ آخری سے اٹھتے ہوئے عصر کی نماز میں بدھ کے دن سمجھائے.ان آیات میں چار باتیں بیان ہوئی ہیں.اوّل اَلْفَجْرِ دوم وَلَیَالٍ عَشْرٍ سوم وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ چہارم وَالَّیْلِ اِذَایَسْرِ.ان چاروں کی قسم دو طرح ہو سکتی ہے یا یہ سارے امور ایک ہی واقعہ کے چار اہم جزو ہیں.یعنی یا تو یہ کہنا پڑے گا کہ ان آیات میں صرف ایک واقعہ کا ذکر کیا گیا ہے مگر اس ایک واقعہ کے چار اہم جزو الگ الگ بیان کر دیئے گئے ہیں اور یہ صورت بالکل جائز ہے.میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ مفسرین کے بیان کردہ معنوں کو ہم مان سکتے تھے بشرطیکہ چاروں باتیں آپس میں منطبق ہو جاتیں مگر چونکہ ان کے پیش کردہ معانی پر تمام آیات پوری نہیں اترتیں اس لئے ہم ان کو تسلیم نہیں کر سکتے.بہرحال ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ یہ ایک ہی واقعہ کے چار اہم جزو ہوں اور یا پھر یہ تسلیم کیا جائے کہ یہ چاروں الگ الگ واقعات ہیں اگر ثابت ہو جائے کہ وَالْفَجْرِ سے اور واقعہ کی
Page 186
طرف اشارہ ہے وَلَیَالٍ عَشْرٍ سے اور واقعہ کی طرف.وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ سے اور واقعہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور وَالَّیْلِ اِذَایَسْرِ سے اور واقعہ کی طرف.تو یہ بھی ایک معقول توجیہ ہو سکتی ہے اور ہم اسے تسلیم کر سکتے ہیں بشرطیکہ یہ چاروں اہم واقعات سے تعلق رکھنے والے امور ہوں اور آپس میں کوئی جوڑ اور تعلق رکھتے ہوں اور یا پھر ان کے متعلق یہ صورت تسلیم کی جا سکتی ہے کہ یہ دو یا تین مجموعے ہیں جن کو بیان کیا گیا ہے مثلاً ثابت کیا جائے کہ فلاں فلاں دو باتیں الگ بیان کی گئی ہیں اور فلاں فلاں دو باتیں الگ بیان کی گئی ہیں اور یہ چار الگ الگ واقعات نہیں بلکہ دو مختلف مجموعے ہیں.یا مثلاً ثابت کیا جائے کہ وَالْفَجْرِ وَلَیَالٍ عَشْرٍ میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے.وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ میں دوسرا اور وَالَّیْلِ اِذَایَسْرِ میں تیسرا.تو یہ بھی درست ہو سکتا ہے غرض یہ تینوں صورتیں ہوسکتی ہیں یا تو یہ سارے امور ایک ہی واقعہ کے چار اہم جزو ہیں یا چاروں الگ الگ واقعات ہیں یا دو یا تین مجموعے ہیں.سابق مفسرین نے ان کو ایک ہی واقعہ کے مختلف حصے قرار دیا ہے اور انہوں نے کوشش کی ہے کہ ایک ہی واقعہ پر لَیَالٍ عَشْرٍ کو چسپاں کریں.اسی کو شفع کا مصداق قرار دیں اور اسی کو وتر قرار دیں.اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا ذہن اس طرف گیا ہے کہ یہ ایک ہی واقعہ کے مختلف حصے ہیں جیسے محر.۱م کی راتیں اور اس کی فجر اور اس کی نمازیں یا ذ۲ی الحجہ کے ایام اس کی راتیں اور بعض دن اور فجر.یا ر۳مضان کی راتیں اس کی کوئی فجر اور بعض راتیں.غرض اس امر میں اتفاق ہے کہ یہ ایک ہی واقعہ کے مختلف پہلو ہیں.مگر جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں بیان کردہ تفسیریں سارے پہلوؤں پر مشتمل ثابت نہیں ہوتیں اور کوئی حقیقت باہرہ ان سے ظاہر نہیں ہوتی.میرے نزدیک فجر چونکہ ایک بیان ہوئی ہے اور راتیں دس بیان ہوئی ہیں حالانکہ دس راتوں کی دس فجریں ہوتی ہیں اور راتوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے.پہلے دس راتوں کا ذکر ہے درمیان میں شفع اور وتر کا ذکر ہے اور آخر میں پھر ایک رات کا ذکر ہے اس لئے میرے نزدیک صحیح مضمون پر پہنچنے کے لئے ہمیں سب سے زیادہ اس امر پر غور کرنے سے مدد مل سکتی ہے کہ یہاں فجر ایک بیان ہوئی ہے اور راتیں دس بیان کی گئی ہیں.پھر ان دس راتوں کے بعد کوئی واقعہ شفع اور وتر کا ہے پھر کسی اور رات کا ذکر کیا گیا ہے جو چلی گئی.گویا دو فجروں کا ذکر کیا گیا ہے.ایک فجر وہ ہے جس کا دس راتوں کے ساتھ تعلق ہے پھر شفع اور وتر کا کوئی واقعہ ہے اور پھر ایک رات کا ذکر ہے جو دور ہو گئی یعنی اس کے بعد پھر ایک اور فجر کا طلوع ہو گیا.اگر ہمیں کسی ایسے واقعہ کا علم حاصل ہو جائے جس میں یہ سب باتیں پائی جائیں اور وہ واقعہ ایسا ہو کہ ان تمام حصوں پر پوری طرح چسپاں ہو جاتا ہو تو دوست اور دشمن کوئی بھی اس کی صحت سے انکار نہیںکر سکتا.پس ان آیات میں پہلے دس راتیں بیان ہوئی ہیں جن کے
Page 187
ساتھ فجر کا تعلق ہے.پھر شفع اور وتر کا ذکر ہے اور پھر ایک رات کے چلے جانے کا.جس کے یہ معنے ہیں کہ یہاں رات پر زور دینا مدنظر نہیں بلکہ رات کے دور ہو جانے پر زور دینا مدنظر ہے لَیَالٍ عَشْرٍ میں رات پر زور دینا مقصود تھا.مگر وَالَّیْلِ اِذَایَسْرِ میں رات کے چلے جانے پر زور دینا مقصود ہے.چونکہ دنیا میں کوئی دس راتیں ایسی نہیں ہوتیں جن کی ایک فجر ہو اور کوئی دس راتیں ایسی نہیں ہوتیں جن کے بعد شفع اور وتر کا کوئی واقعہ ہو اور کوئی شفع اور وتر کا واقعہ ایسا نہیں ہوتا جس کے بعد ایک رات ہواس لئے لازماً تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ اس جگہ جن راتوں کا ذکر کیا گیا ہے ان کا مادی سورج کے چڑھنے اور ڈوبنے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور ایک رات سے مراد بھی کوئی ایسی رات نہیں جس میں سورج ایک طرف سے چڑھتا اور دوسری طرف نکل جاتا ہے کیونکہ دس راتوں کے بعد ایک فجر نہیں ہوتی.اور نہ دس راتوں اور ایک رات کے درمیان کوئی شفع اور وتر ہوتا ہے پس یہاں ظاہری راتیں کسی صورت میں مراد ہی نہیں ہو سکتیں.بلکہ عقلاً تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ اس جگہ رات اور فجر کے الفاظ استعارۃً استعمال ہوئے ہیں نہ کہ حقیقی معنوں میں.کیونکہ کوئی ظاہری دس راتیں ایسی نہیں ہوتیں جن کے بعد ایک فجر ہو.کوئی ظاہری دس راتیں ایسی نہیں ہوتیں جن کے بعد شفع اور وتر کا کوئی واقعہ ہو.اور کوئی ظاہری ایک رات ایسی نہیں ہوتی جس کے بعد فجر ہی فجر رہے.پھر راتوں کے ذکر میں یہ فرق پایا جاتا ہے کہ لَیَالٍ عَشْرٍ میں تورات کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے مگر ایک رات کے ذکر میں اس رات کے جانے اور دن کے نکل آنے پر زور دیا گیا ہے.سورۂ فجر کی پہلی چار آیات میں واقعاتی ترتیب الغرض میرے نزدیک اس آیت کی ترتیب یوں ہے.د۱س راتیں پھر ا۲یک فجر اور اس کے بعد ۳شفع اور وتر کا کوئی واقعہ اور پھر ایک را۴ت اور پھر ایک طویل فجر.گویا اس واقعہ میں دس راتوں کے بعد ایک فجر اور اس کے بعد ایک شفع و وتر کا واقعہ اور اس کے بعد ایک رات اور ایک لمبی فجر کا ذکر ہے.پہلی فجر کو دس راتوں سے پہلے اس لئے بیان کیا گیا ہے (حالانکہ فجر رات کے بعد ہوتی ہے) کہ یہ امر واضح تھا کہ رات سے پہلے فجر نہیں ہوتی بلکہ بعد میں ہوتی ہے.باقی رہا یہ امر کہ فجر کا ذکر پہلے اور راتوں کا ذکر بعد میں کرنے کی وجہ کیا ہے؟ سو اس کا جواب یہ ہے کہ فجر کے لفظ میں ایک خوشخبری تھی اور دنیا میں یہ ایک عام طریق ہے کہ جب ہم اپنے دوست سے کسی ایسے واقعہ کا ذکر کرتے ہیں جو تکلیف دہ ہو لیکن اس کا انجام اچھا ہو تو ہم اس کے خوش انجام کا ذکر پہلے کر دیتے ہیں اور غم انگیز حصہ کو بعدمیں بیان کرتے ہیں تا اسے زیادہ صدمہ نہ ہو.مثلاًاگر ہمارا کوئی دوست بیمار ہو اور کوئی شخص اس کی تیمارداری کے لئے جائے اور اس بیمار کی حالت پہلے سے اچھی ہو
Page 188
اور وہ آ کر پہلے بیماری کی تفاصیل نہیں شروع کر دے گا بلکہ مثلاً یوں کہے گا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اب اچھے ہیں بیچ میں تو خطرہ پیدا ہو گیا تھا.یہ نہیں ہوتا کہ وہ پہلے تفصیلی حالات بیماری کی تکالیف کے سنانے لگ جائے اور اس کی خیریت کے متعلق بعد میں جا کر خبر دے.چنانچہ اُحد کے موقع پر جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر لوگوں میںمشہور ہوئی اور مدینہ سے عورتوں اور بچوں کا ایک گروہ اُحد کے میدان کی طرف چل پڑا تو اس وقت اسلامی لشکر واپس آ رہا تھا ایک عورت بے تابانہ آگے بڑھی اور اس نے ایک مسلمان سپاہی سے دریافت کیا بتاؤ رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم کا کیا حال ہے؟ اس نے بجائے اس کے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت کی خبر اسے دے یہ جواب دیا کہ تمہارا خاوند اس جنگ میں مارا گیا ہے.اس نے کہا میں تم سے اپنے خاوند کی خبر دریافت نہیں کر رہی پہلے یہ بتاؤ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ اور جب اس نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں تو عورت خوشی سے بول اٹھی کہ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں تو پھر مجھے اپنے کسی غم کی پروا نہیں ہے(السیرۃ النبویۃ لابن ہشام غزوۃ احد) تو دیکھ لو اس عورت نے خوشی کی خبر پہلے سننی چاہی اور غم کی بعد میں.اس نے سمجھا کہ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں تو میرا دل اس خوشی کی خبر کی وجہ سے اور صدمات کو برداشت کر سکتا ہے لیکن اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نہیں تو پھر میرا دل کسی صدمہ کو برداشت نہیں کر سکتا.توقاعدہ یہی ہے کہ جب خوشی اور غم کسی خبر کا جزو ہوں تو پہلے خوشی کی خبر سنائی جاتی ہے تا کہ غم کی خبر زیادہ تکلیف نہ دے.پس چونکہ خوشی کی خبر پہلے بیان کی جانی تبشیر کے موقع پر زیادہ مناسب ہوتی ہے اس لئے بجائے یوں کہنے کے کہ ہم دس راتوں اور ان کے بعد کی فجر کو بطور شہادت بیان کرتے ہیں یہ فرمایا کہ ہم فجر اور اس سے پہلے آنے والی دس راتوں کو بطور شہادت بیان کرتے ہیں.اگر پہلے ہی دس راتوں کا ذکر کر دیا جاتا تو مسلمان اس خبر کو سن کر کانپ اٹھتے ان کے دل لرز جاتے اور وہ سخت فکر اور غم میں مبتلا ہو جاتے کہ نہ معلوم اب کیا بننے والا ہے.اس لئے اللہ تعالیٰ نے بجائے یہ فرمانے کے کہ ہم دس راتوں اور ان کے بعد کی فجر کو بطور شہادت پیش کرتے ہیں یہ کہہ دیا کہ ہم فجر اور اس سے پہلے آنے والی دس راتوں کو بطور شہادت پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد ہونے والے ایک شفع اور وتر کے واقعہ کو اور پھر اس کے بعد ایک رات کے چلے جانے یعنی صبح کو بطور شہادت پیش کرتے ہیں گویا بات تو وہی رہی مگر مومنوں کے دلوں کو تسلی ہو گئی کہ کسی خاص فکر کی ضرورت نہیں آخر نتیجہ ہمارے حق میں ہی نکلے گا چنانچہ اس خبر کو لَیَالٍ عَشْرٍ سے شروع کرنے کی بجائے وَالْفَجْرِ سے شروع کیا اور مسلمانوں کو بتایا کہ اب جو خبر
Page 189
آرہی ہے اس سے یہ نہ سمجھنا کہ آخری نتیجہ تمہارے حق میں خراب نکلے گا.آخری نتیجہ بہرحال اچھا ہو گا اور اس کو ہم ان راتوں کے ذکر سے پہلے ہی بیان کر دیتے ہیں تا کہ تمہارے دل مطمئن رہیں اور اس خبر سے پریشان نہ ہوں.پس یہاں رات کا لفظ حقیقی معنوںمیں استعمال نہیں کیا گیا بلکہ استعارۃً استعمال کیا گیا ہے کیونکہ کوئی ظاہری دس راتیں ایسی نہیں ہوتیں جن کی ایک فجر ہو ہاں استعارۃً دس راتوں کی ایک فجر ہو سکتی ہے.بہرحال یہ چار واقعات ہیں جن کا سورۃ الفجر کی ان چار آیات میں ذکر آتا ہے.پہلے یہ خبر دی گئی ہے کہ دس راتیں آئیں گی پھر یہ خبر دی گئی ہے کہ ان دس راتوں کے بعد فجر آئے گی پھر یہ خبر دی گئی ہے کہ ایک شفع اور وتر کا واقعہ ہو گا اور پھر یہ خبر دی گئی ہے کہ ایک رات ہے جو چلی جائے گی.ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ کون سے واقعات ہیں جن کا ان آیات میں ذکر آتا ہے.اگر ہم قیاسات سے کام لیں اور محض عقلی ڈھکونسلوں تک اپنے آپ کو محدود رکھیں تو یقیناً ہم کسی صحیح نتیجہ پر نہیں پہنچ سکتے اور ہم اسی رو میں بہتے چلے جائیں گے جس رو میں سابق مفسرین بہہ گئے.ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم ان واقعات کو قرآن کریم سے ثابت کریں.ہم ان واقعات کو اسلامی تاریخ سے ثابت کریں.ہم ان واقعات کو مہتم بالشان واقعات سے ثابت کریں اور ہم علیٰ وجہ البصیرت اس بات کو بیان کر سکیں کہ یہ وہ واقعات ہیں جن کی طرف قرآن کریم نے اشارہ کیا ہے، جو اسلام کی سچائی سے گہرا تعلق رکھتے ہیں، جن میں قرآنی ترتیب پوری طرح پائی جاتی ہے اور جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے لئے بطور ثبوت اور حجت کفار کے سامنے پیش کئے جا سکتے ہیں.اگر ایسے واقعات ہمیں قرآن کریم سے مل جائیں، اسلامی تاریخ سے مل جائیں، ترتیب آیات پر وہ پورے اتریں اور پھر اسلام اور رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم کی صداقت کا بھی زندہ ثبوت ہوں تو یقیناً انہی واقعات کی طرف ان آیات میں اشارہ سمجھا جائے گا.میں نے اس سورۃ پر سوچا اور سوچا مگر آخر معاً بطور القا اس کا حل مجھے ملا.سورۂ فجر میں دس راتوں سے مراد مسلمانوں کی مخالفت کے دس سال میں یہ بتا چکا ہوں کہ دس راتوں کا ذکر محلًّا پہلے ہے گو ذکراً دوسرے نمبر پر ہے اور میں یہ بھی بتا چکا ہوں کہ یہ دس راتیں عام راتیں نہیں بلکہ استعارۃً ان کو راتیں کہا گیا ہے.پھر میں یہ بھی بتا چکا ہوں کہ یہ سورۃ تیسرے سال کے آخر میں نازل ہوئی ہے جب ابھی منظم مخالفت اسلام کی شروع نہیں ہوئی تھی.جب ابھی مسلمانوں کو کچلنے اور ان کو تباہ وبرباد کرنے کے
Page 190
منصوبے اجتماعی طور پر کفار نے شروع نہیں کئے تھے.وہ انفرادی طور پر تو اذیت پہنچانے کی کوشش کرتے تھے مگر اکثر ایسے تھے جو اسلام کو مذاق میں اڑا دیتے تھے.وہ مسلمانوں کو پاگل اور مجنون کہہ کر خاموش ہو جاتے اور سمجھتے کہ یہ چند سر پھرے لوگ ہیں انہوںنے ہمارا کیا بگاڑ لینا ہے خود ہی چند دنوں تک خاموش ہو جائیں گے.عملی مخالفت جو انہوں نے بعد میں ایک تنظیم کے ماتحت کی اور جس میں مسلمانوں کو بڑے بڑے دکھ پہنچائے گئے وہ ابھی شروع نہیں ہوئی تھی.قریبًا تین سال رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم کے دعویٰ نبوت پر گذر چکے تھے کہ اس وقت خدا تعالیٰ نے اس سورۃ کو نازل کیا اور مسلمانوں کو بتایا کہ اب تمہاری شدید ترین مخالفت ہونے والی ہے.مصائب اور تکالیف کی بھیانک راتیں تم پر چھا جانے والی ہیں.ایک کے بعد ایک رات آئے گی مگر کامیابی کی کوئی شعاع تمہیں نظر نہیں آئے گی اور یہ سلسلہ ممتد ہوتا چلا جائے گا یہاں تک کہ پورے دس سال تمہیں ان مصائب اور مشکلات کا تختۂ مشق بننا پڑے گا.اب غور کر لو یہ بات کس حیرت انگیز طور پر پوری ہوئی.تیسرے سال کے آخر میں یہ سورۃ نازل ہوتی ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیرہ سال تک مکہ میں رہے ہیں.پہلے تین سال مخالفت نہیں ہوئی لیکن اس کے بعد مکہ والوں نے شدید ترین مخالفت شروع کر دی.تیرہ۱۳ میں سے تین۳ سال نکال دو تو باقی ٹھیک دس سال رہ جاتے ہیں جن میںمسلمان کفار کا تختۂ مشق بنے رہے اور یہی وہ دس سال تھے جن کی لَیَالٍ عَشْرٍ میں خبر دی گئی تھی اور جن کو مشکلات اور مصائب کے ہجوم کی وجہ سے استعارۃً رات قرار دیا گیا تھا.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے جو تمہیں عَامِلَۃٌ نَّاصِبَۃٌ میں خبر دی تھی کہ اب یہ لوگ منظم مخالفت شروع کرنے والے ہیں وہ وقت اب آپہنچا ہے.مصائب کا ایک شدید دَور تم پر اور تمہارے ساتھیوں پر آنے والا ہے، تاریک ترین راتیں، انتہائی بھیانک راتیں، جسم کو کپکپا دینے والی راتیں، لرزہ بر اندام کر دینے والی راتیں، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، مسلسل دس راتیں آئیں گی اور تم کو اور تمہاری قوم کو سخت مصیبت دیکھنی پڑے گی مگر اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیشتر اس کے کہ ہم ان تاریک راتوں کی خبر دیںپہلے ہی تمہیں یہ خوشخبری سنا دیتے ہیں کہ ان راتوں کے بعد فجر آنے والی ہے، بےشک مخالفت ہو گی اور شدید ہو گی مگر انجام بہرحال اچھا ہو گا.اسلام پھیلے گا، مسلمان غالب آئیں گے، اور مشکلات کے بادل دس سال گذرنے کے بعد پھٹ جائیں گے اور فجر ظاہر ہو جائے گی.چنانچہ ٹھیک چوتھے سال مکہ والوں نے اسلام اور مسلمانوں کی منظم مخالفت شروع کر دی اور مسلمانوں پر تاریک راتیں چھا گئیں.
Page 191
اس بات کا ثبوت کہ مسلمانوں کی اصل مخالفت دعویٰ نبوت کے چوتھے سال شروع ہوئی یہ ایک ثابت شدہ حقیقت ہے کہ یہ سورۃ تیسرے سال کے آخر یا چوتھے سال کے شروع کی ہے اور مکہ والوں کی طرف سے منظم مخالفت چوتھے سال میں شروع ہوئی ہے اسلامی تاریخ اس پر متفق ہے اور یوروپین مصنّف بھی گو اسلام کے دشمن ہیں مگر تاریخی اعتبار سے یہ گواہی دینے پر مجبور ہوئے ہیں چنانچہ میور لکھتا ہے."It was not however till three or four years of his ministry had elapsed that any general opposition to Mohammad was organised." (The Life of Mahomet by Sir William Muir P:68) یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت آپ کے دعویٰ کے تین چار سال بعد تک منظم صورت میں ظاہر نہیں ہوئی.آرگنائزڈ اور منظم مخالفت جس میں تمام قوم آپ کے خلاف کھڑی ہو گئی اور چھوٹوں بڑوں سب نے مل کر اسلام کو مٹانا چاہا وہ دعویٰ کے ابتدائی تین چار سالہ دَور میں نظر نہیں آتی.آرگنائزڈ مخالفت جیسا کہ نَاصِبَۃٌ کی تشریح میں بتایا جا چکا ہے یہ ہوتی ہے کہ باقاعدہ افسر مقرر کئے جاتے ہیں.مختلف لیڈر کھڑے کئے جاتے ہیں اور ان سب سے کہا جاتا ہے کہ تم نے مل کر حملہ کرنا ہے اس قسم کی منظم مخالفت میور کے نزدیک ابتدائی تین چار سالوں میں شروع نہیں ہوئی.پھر لکھتا ہے:."Even after he had begun publicly to summon his fellow citizens to the faith, and his followers had multiplied the people did not gainsay his doctrine." (The Life of Mahomet by Sir William Muir P:68) اس وقت کے بعد بھی کہ آپ نے اعلانیہ اہلِ شہر کو دعوت اسلام دینی شروع کی اور باوجود اس کے کہ آپ پر ایمان لانے والے بڑھنے لگ گئے تھے لوگ آپ کی بات کی تردید کی ضرورت نہ سمجھتے تھے.یہ خیال ہو سکتا تھا کہ جب چند آدمی آپ کو مان چکے تھے اور آپ کے دعویٰ کو تسلیم کر چکے تھے تو بہرحال لوگوں میں آپ کے خلاف جوش پیدا ہو چکا ہو گا بالخصوص اس وجہ سے کہ آپ نے لوگوں میں وعظ شروع کر دیا تھا اور لوگوں کو اپنے مذہب کی تلقین شروع کر دی تھی.مگر میور لکھتا ہے یہ خیال درست نہیں باوجود اس کے کہ انہوں نے
Page 192
لوگوں کو اعلانیہ اپنے مذہب کی تبلیغ شروع کرد ی تھی اور ان کے ماننے والوں کی تعداد بھی بڑھنے لگ گئی تھی لوگ یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم ان کو کچل دیں گے یا ان کے مذہب کو مٹا دیں گے.بلکہ "They would only point at him slightingly as he passed and say there goeth the fellow from among the children of Abdul Muttalib to speak unto the people about the heavens." (The Life of Mahomet by Sir William Muir P:68) وہ ان کی طرف حقارت اور نفرت سے دیکھتے ہوئے کہتے دیکھو وہ عبدالمطلب کی اولاد میں سے ایک شخص جارہا ہے جو آسمان کی خبریں لوگوں کو سناتا ہے.مگر تیسرے سال کے آخر یا چوتھے سال کے شروع میں انہوں نے اسلام کی آرگنائزڈ مخالفت کا فیصلہ کیا.ریورنڈ ویری لکھتے ہیں:."This would be, as Noeldeke has it, about the fourth year of his ministry at Makkah." (A comprehensive Commentary on Quran by Wherry; Vol:iv P:239) محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلی اور منظم مخالفت جو مکہ میں ہوئی وہ جیسا کہ نولڈکے کا خیال ہے تیسرے سال کے آخر یا چوتھے سال کے شروع میں ہوئی ہے.پھر دیکھو سورۂ فجر کی نسبت لکھتے ہیں:.He (Noeldeke) however regards it as early Makkan and in his chronological table places it immediately after chapter LXXX VIII.(A comprehensive Commentary on Quran by Wherry; Vol:iv P:242) یعنی نولڈکے اس سورۃ کو ابتدائی مکی سورتوں میں شمار کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ غاشیہ کے معاً بعد نازل ہوئی ہے اور غاشیہ کے متعلق یہ بتایا جاچکا ہے کہ اس کا نزول چوتھے سال کے قریب ہوا ہے جب کہ مسلمانوں پر کفار مکہ کے مظالم شروع ہونے والے تھے.
Page 193
غرض یوروپین اور مسلمان مؤرخ سب اس بات پر متفق ہیں کہ یہ سورۃ چوتھے سال کے قریب نازل ہوئی ہے اور یہی وہ سال ہے جس میں کفار مکہ کی طرف سے منظم مخالفت کا آغاز ہوا اور انہوں نے مسلمانوں کو شدید ترین مصائب میں مبتلا کرنا شروع کر دیا.میور تسلیم کرتا ہے کہ ابتدائی تین سالوں میں مسلمانوں کی کوئی قابلِ ذکر مخالفت نہیں تھی.وہ مسلمانوں کودیکھتے تو تمسخر اور استہزاء سے کام لے کر گذر جاتے.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کرتے دیکھتے تو حقارت سے کہتے یہ ایک پاگل ہے جو لوگوں کو آسمان کی باتیں سنا رہا ہے.مگر چوتھے سال کے شروع میں جیسا کہ وُجُوْهٌ يَّوْمَىِٕذٍ خَاشِعَةٌ.عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ میںخبر دی گئی تھی انہوں نے کھلی اور منظم مخالفت شروع کر دی.اسلام کو مٹانے کے لئے ان کے چھوٹے اور بڑے سب متحد ہو گئے اور انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم مسلمانوں کو کچل کر رکھ دیں گے.غرض تاریخی شہادتیں اس بات پر متفق ہیں کہ مسلمانوں پر منظم ظلم چوتھے سال میںشروع ہواہے یعنی ہجرت سے دس سال پہلے ( تاریخ الخمیس جلد ۱ صفحہ ۲۸۷ تا ۲۸۹ ).اور یہ سورۃ اسی زمانہ میں نازل ہوئی ہے.پس دس راتوں میں ظلم وتعدی کے ان دس سالوں کی خبر دی گئی ہے جن میں انسانیت اور شرافت کا مکہ والوں نے جنازہ نکال دیا تھا اور منظم ظلم کے شروع ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ اب مکہ والے عَامِلَۃٌ نَّاصِبَۃٌ بننے و الے ہیں، ان کی طرف سے ظلم وستم کا بازار گرم ہونے والا ہے اور وہ اسلام کے خلاف اپنا پورا زور صرف کرنے والے ہیں.انفرادی طور پر بھی اور جماعتی طور پر بھی.اور یہ مظالم برابر دس سال تک چلے جائیں گے کہ ہر ایک سال ایک رات کی طرح ہو گا جس میں امید کی کوئی شعاع لوگوں کو نظر نہیں آئے گی مگر آخر ان دس راتوں کے گذرنے کے بعد جو انتہائی دکھ اور تکلیف کی راتیں ہوں گی اللہ تعالیٰ فجر کا طلوع کر دے گا یعنی مصائب اور تکالیف کی یہ راتیں کٹ جائیں گی اور ایک نیا دور مسلمانوں کی ترقی کا شروع ہو جائے گا.یہ فجر اس طرح ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی رنگ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبر مدینہ میں پہنچا دی.یہودی لوگ مشرکین سے کہا کرتے تھے کہ ہماری کتابوں میں ایک آنے والے موعود کی خبر پائی جاتی ہے اور آثار سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ عنقریب آنے والا ہے جب وہ آئے گا تو دنیا میں خدا تعالیٰ کی بادشاہت کو قائم کرے گا وہ لوگ اس کے معنے یہودیت کی حکومت کے سمجھتے تھے اور خیال کرتے تھے کہ اس موعود کے آنے پر ہمیں حکومت حاصل ہو جائے گی(السیرۃ النبویۃ لابن ہشام زیر عنوان انذار یـھود برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ) کیونکہ خدا تعالیٰ کے منشا کا ان کو علم نہیں تھا.چونکہ مشرکین یہود سے بالعموم اس قسم کی باتیں سنتے رہتے تھے اور یہود ان سے تعلیم اور مال
Page 194
میں بھی زیادہ تھے گو تعداد کے لحاظ سے مشرکین زیادہ تھے اس لئے جب ان کے کان میں یہ خبر پہنچی کہ مکہ میں ایک شخص ظاہر ہوا ہے جو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے باتیں کرتا ہے تو ان کے دلوں میں یہ خیال گذرا کہ اگر وہ سچاہوا اور وہی ہوا جس کا یہود ذکر کیا کرتے ہیں تو پھر کیا ہو گا.ایسا نہ ہو کہ یہود اس پر ایمان لا کر ہم سے سبقت لے جائیں اور حکومت پر قبضہ کر لیں.یہودی ان سے کہا کرتے تھے کہ ہم اس موعود کے آنے پر جب بادشاہت حاصل کر لیں گے تو تمہاری خوب خبر لیں گے.ان باتوں کو سنتے رہنے کی وجہ سے قبائل مدینہ کو آنے والے کا خاص خیال رہتا تھا جب انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبر سنی تو فوراً خیال آیا کہ اگر یہ مدعی سچا ہے تو ایسا نہ ہو یہود اسے ہم سے پہلے مان لیں.ان میں سے بعض لوگ مکہ حج کے لئے گئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے آپ کی باتیں سن کر آپ کی صداقت کا انہیں یقین ہو گیا اور وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے اسلام میں داخل ہو گئے.پھر اور لوگ آئے پھر اَور لو گ آئے یہاں تک کہ ایک کافی تعدار مدینہ کے لوگوں کی اسلام میں داخل ہو گئی.اس پر بعض نے کہا کہ مکہ والے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر نہیں کرتے کیوں نہ ہم آپؐکو اپنے پاس بلوا لیں.چنانچہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم کی خدمت میں اپنا وفد بھیجا اور عرض کیا کہ آپ ہمارے ہاں تشریف لے آئیں ہماری قوم قریباً سب کی سب مسلمان ہونے کے لئے تیا ر ہے.آپ نے فرمایا اگر خدا تعالیٰ مجھے اجازت دے گا تو میں ہجرت کر کے آ جاؤں گا.اس پر بعض نے کہا کہ ایسا نہ ہو اللہ تعالیٰ جب آپ کو غلبہ عطا فرمائے تو آپ واپس اپنے وطن میں آجائیں.آپ نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا.(السیرۃ النبویۃ لابن ہشام زیر عنوان امر العقبۃ الثانیۃ) فجر کے طلوع سے مراد آنحضرت صلعم کی ہجرت آخر خدا تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم کو ہجرت کی اجازت دی اور آپ مدینہ تشریف لے گئے.یہ ہجرت وہی فجر ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں کیا گیا ہے اور جس سے اسلام کے سورج کا طلوع ہوا.اور جس سے اسلامی سال آج تک چل رہا ہے اور قیامت تک چلے گا.اسی ہجرت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ یوں فرمایا ہے رَبِّ اَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِيْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّ اجْعَلْ لِّيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا (بنی اسـراءیل:۸۱) دیکھو یہاں ہجرت سے زیادہ خوشخبری یعنی داخلہ مکہ کا ذکر پہلے کیا ہے اور ہجرت کا ذکر جو زماناً مقدم ہے بعدمیں کیا ہے.اسی طرح مکہ والوں کے دس سالہ مظالم کے مقابلہ پر ہجرت ایک نعمت تھی اس کا ذکر پہلے کیا ہے اور دس راتوں کا جو زماناً مقدم تھیں بعد میں ذکر کیا ہے.ہجرت کا ذکر قرآن کریم میں کئی جگہ کیا گیا ہے.جس طرح وہ دس تکالیف کے سال اسلامی تاریخ میں ایک اہم جگہ رکھتے ہیں اسی طرح ہجرت بھی ایک اہم جگہ رکھتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ
Page 195
يَجْعَلْ لَّكُمْ فُرْقَانًا وَّ يُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ١ؕ وَ اللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ.وَ اِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِيُثْبِتُوْكَ اَوْ يَقْتُلُوْكَ اَوْ يُخْرِجُوْكَ١ؕ وَ يَمْكُرُوْنَ وَ يَمْكُرُ اللّٰهُ١ؕ وَ اللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ(الانفال:۳۰،۳۱) فرماتا ہے اے مومنو! اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرو اگر تم تقویٰ اختیار کرو گے تو وہ تمہاری کامیابی کے بیسیوںرستے پیدا کر دے گا.تمہاری کوتاہیوں کو دور کرے گا اور تمہاری کمزوریوں پر پردہ ڈال دے گا اور اللہ بڑے فضلوں والا ہے.چنانچہ ہم تمہارے سامنے اس کی ایک مثال پیش کرتے ہیں تاکہ تمہیں یہ خیال نہ ہو کہ یہ محض قیاسی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑے فضلوں والا ہے سواے ہمارے رسول! تم بھی یاد کرو اور لوگوں کے سامنے بھی اس واقعہ کو پیش کرو کہ ہمارا خدا کیسا وفادار خدا ہے.کتنی بڑی طاقتوں اور قدرتوں کا مالک خدا ہے.جب تمہارے متعلق کفار نے مختلف منصوبے شروع کر دیئے تھے اور ان منصوبوں سے ان کی غرض یہ تھی کہ اے ہمارے رسول! تجھے قید کر دیں یا تجھے قتل کر دیں یا تجھے اپنے گھر سے باہر نکال دیں.یہ تین تدبیریں تھیں جن کا تیرے خلاف انتظام کیا جا رہا تھا.وہ چاہتے تھے کہ تجھے قید کر دیں.وہ چاہتے تھے کہ تجھے قتل کر دیں وہ چاہتے تھے کہ تجھے اپنے شہر سے نکال دیں.یہ مطلب نہیں کہ بیک وقت وہ ان تینوں تدبیروں پر عمل کرنا چاہتے تھے بلکہ مطلب یہ ہے کہ ان میں سے بعض ایسے تھے جنہوں نے دورانِ مشورہ میںیہ رائے دی کہ اس شخص کا معاملہ اب حد سے بڑھ گیا ہے اور مدینہ کے لوگ بھی اس پر ایمان لانے لگ گئے ہیں اگر یہ اسی طرح ترقی کرتا چلا گیا تو ہمارے لئے یہ بات نہایت خطرناک ہو گی.بہتر یہ ہے کہ اسے قید کر دیا جائے تاکہ نہ یہ لوگوں سے مل سکے اور نہ اپنی تبلیغ کو پھیلا سکے.دوسروں نے کہا کہ یہ مناسب نہیں اگر ہم نے اسے قید کر دیا تو اس کے رشتہ داروں اور ماننے والوں کو جب اس کا پتہ چلا تو وہ جوش میں آکر لڑنے پر آمادہ ہو جائیں گے اور اس طرح قوم میں فساد ہو گا اس لئے ہمارے نزدیک بہتر یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے تاکہ یہ جھگڑا ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائے اور اس کے رشتہ دار بھی یہ سمجھ کر کہ اب تو ہمارا عزیز مارا ہی جا چکا ہے اب قوم سے لڑائی مول لینے کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ وہ تو واپس آ نہیں سکتا صبر سے کام لیں.بعض اور لوگوں نے کہا کہ قتل کرنا مناسب نہیں اس کے قتل پر شور مچ جائے گا اور بالکل ممکن ہے کہ بنو ہاشم بدلہ لینے کے لئے ہم سے لڑائی شروع کر دیں اور جیسا کہ بعض دوسروں کا خیال ہے کہ صبر کر کے بیٹھ جائیں واقع میں ایسا نہ ہو پس بہتر یہ ہے کہ اسے مکہ سے نکال دیا جائے.وہ لوگ جو اخراج کی تدبیر کے خلاف تھے انہوں نے کہا کہ یہ کوئی اچھی تجویز نہیں.ہمارا مقصد تو اس کے مشن کو ناکام کرنا ہے.اگر یہ باہر جا کر اپنی باتوں کو پھیلانے لگ گیا تو تمام عرب تمہارے خلاف ہو جائے گا.(السیرۃ النبویۃ لابن ہشام زیر عنوان ہجرۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ) غرض مختلف تجاویز پیش ہوئیں کسی پر
Page 196
کوئی اعتراض ہوتا اور کسی پر کوئی.مگر آخر انہوں نے فیصلہ کیا کہ اصل علاج یہی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے پس چونکہ انہوں نے تین تجویز یںکی تھیں اس لئے قرآن کریم نے بھی ان تینوں تجویزوں کا ذکر کر دیا.پہلے تثبیت کا ذکر کیا پھر قتل کا ذکر کیا پھر اخراج کا ذکر کیا.دیکھو اس جگہ قتل جو بڑی چیز تھی اللہ تعالیٰ نے اس کا درمیان میں ذکر کیا ہے اور قید اور جلاوطنی جو اس سے کم درجہ کی چیزیں تھیں ان کو دائیں بائیں رکھ دیا ہے یہ وہی ترتیب ہے جس کا میں اَفَلَا يَنْظُرُوْنَ اِلَى الْاِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ.وَ اِلَى السَّمَآءِ كَيْفَ رُفِعَتْ کی تفسیر میں ذکر کر چکا ہوں کہ بعض دفعہ ایک بڑی چیز کو درمیان میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس سے چھوٹی چیزوں کو دائیں بائیں.گویا یہ کلام مثلّث کی شکل کا ہو تا ہے دو۲ مشورے جو ادنیٰ تھے ان کو خدا تعالیٰ نے دائیں بائیں بیان کر دیا اور جو زیادہ سخت اور چوٹی کا مشورہ تھا اسے درمیان میں رکھ دیا.بہرحال آخری فیصلہ انہوں نے یہی کیا کہ آپ کو قتل کر دیا جائے.قید کرنا یا آ پ کو مکہ سے باہر نکال دینا مناسب نہیں اس میں زیادہ خطرات ہیں اگر جھگڑا ختم کرنا ہے تو اس کا طریق یہی ہے کہ حملہ کر کے آپ کو مار ڈالا جائے.اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ان کا آخری فیصلہ قتل کا ہی تھا مگر قرآن کریم نے ان کے تینوں مشوروں کا ذکر کیا ہے جس کی حکمت میں آگے چل کر بیان کروں گا.اللہ تعالیٰ ان کے تینوں مشوروں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے يَمْكُرُوْنَ وَ يَمْكُرُ اللّٰهُ١ؕ وَ اللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ.انہوں نے تین منصوبے کئے خواہ آخر میں قتل پر ہی متفق ہو گئے اور میں نے بھی ان کے مقابلہ میں تین تدبیریں کیں بعض نے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم کو قید کر دینا چاہیے.بعض نے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم کو قتل کر دینا چاہیے اور بعض نے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم کو جلاوطن کر دینا چاہیے.خدا تعالیٰ نے ان کی تدبیروں کو سنا اور اس نے کہا بہت اچھا میں تم سے یہ تینوں کام کرواؤں گا اور پھر تمہیں ان تینوں کاموں میں ناکام ونامراد کرکے دکھا دوں گا.تم قتل کا منصوبہ کرو گے اور ذلیل و رسوا ہو گے.تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر و گے اور ذلیل ورسوا ہو گے.تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے باہر نکال دو گے اور ذلیل و رسوا ہوگے.فرض کرو وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ کرتے اور اس میں کامیاب ہو جاتے گو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو قتل نہیں ہو سکتے تھے کیونکہ آپ شرعی نبی تھے اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت آپ کے ساتھ تھی.لیکن بفرضِ محال اگر وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو جاتے اور اس کے بعد بنوہاشم بدلہ لینے کے لئے جنگ شروع کر دیتے اور کفار میں سے بڑے بڑے لوگ مارے جاتے تو وہ لوگ جنہوں نے قید یا جلاوطن کرنے کا مشورہ دیا تھا خوش ہوتے اور کہتے ہم نے نہیں کہا تھا کہ تم اسے قتل نہ کرو تم نے ہمارا مشورہ نہ مانا اور یہ نقصان اٹھایا.یا فرض کرو
Page 197
کوئی اعتراض ہوتا اور کسی پر کوئی.مگر آخر انہوں نے فیصلہ کیا کہ اصل علاج یہی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے پس چونکہ انہوں نے تین تجویز یںکی تھیں اس لئے قرآن کریم نے بھی ان تینوں تجویزوں کا ذکر کر دیا.پہلے تثبیت کا ذکر کیا پھر قتل کا ذکر کیا پھر اخراج کا ذکر کیا.دیکھو اس جگہ قتل جو بڑی چیز تھی اللہ تعالیٰ نے اس کا درمیان میں ذکر کیا ہے اور قید اور جلاوطنی جو اس سے کم درجہ کی چیزیں تھیں ان کو دائیں بائیں رکھ دیا ہے یہ وہی ترتیب ہے جس کا میں اَفَلَا يَنْظُرُوْنَ اِلَى الْاِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ.وَ اِلَى السَّمَآءِ كَيْفَ رُفِعَتْ کی تفسیر میں ذکر کر چکا ہوں کہ بعض دفعہ ایک بڑی چیز کو درمیان میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس سے چھوٹی چیزوں کو دائیں بائیں.گویا یہ کلام مثلّث کی شکل کا ہو تا ہے دو۲ مشورے جو ادنیٰ تھے ان کو خدا تعالیٰ نے دائیں بائیں بیان کر دیا اور جو زیادہ سخت اور چوٹی کا مشورہ تھا اسے درمیان میں رکھ دیا.بہرحال آخری فیصلہ انہوں نے یہی کیا کہ آپ کو قتل کر دیا جائے.قید کرنا یا آ پ کو مکہ سے باہر نکال دینا مناسب نہیں اس میں زیادہ خطرات ہیں اگر جھگڑا ختم کرنا ہے تو اس کا طریق یہی ہے کہ حملہ کر کے آپ کو مار ڈالا جائے.اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ان کا آخری فیصلہ قتل کا ہی تھا مگر قرآن کریم نے ان کے تینوں مشوروں کا ذکر کیا ہے جس کی حکمت میں آگے چل کر بیان کروں گا.اللہ تعالیٰ ان کے تینوں مشوروں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے يَمْكُرُوْنَ وَ يَمْكُرُ اللّٰهُ١ؕ وَ اللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ.انہوں نے تین منصوبے کئے خواہ آخر میں قتل پر ہی متفق ہو گئے اور میں نے بھی ان کے مقابلہ میں تین تدبیریں کیں بعض نے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم کو قید کر دینا چاہیے.بعض نے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم کو قتل کر دینا چاہیے اور بعض نے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم کو جلاوطن کر دینا چاہیے.خدا تعالیٰ نے ان کی تدبیروں کو سنا اور اس نے کہا بہت اچھا میں تم سے یہ تینوں کام کرواؤں گا اور پھر تمہیں ان تینوں کاموں میں ناکام ونامراد کرکے دکھا دوں گا.تم قتل کا منصوبہ کرو گے اور ذلیل و رسوا ہو گے.تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر و گے اور ذلیل ورسوا ہو گے.تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے باہر نکال دو گے اور ذلیل و رسوا ہوگے.فرض کرو وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ کرتے اور اس میں کامیاب ہو جاتے گو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو قتل نہیں ہو سکتے تھے کیونکہ آپ شرعی نبی تھے اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت آپ کے ساتھ تھی.لیکن بفرضِ محال اگر وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو جاتے اور اس کے بعد بنوہاشم بدلہ لینے کے لئے جنگ شروع کر دیتے اور کفار میں سے بڑے بڑے لوگ مارے جاتے تو وہ لوگ جنہوں نے قید یا جلاوطن کرنے کا مشورہ دیا تھا خوش ہوتے اور کہتے ہم نے نہیں کہا تھا کہ تم اسے قتل نہ کرو تم نے ہمارا مشورہ نہ مانا اور یہ نقصان اٹھایا.یا فرض کرو
Page 198
مناسب وقت سمجھا تو اندر داخل ہوئے اور شاید انہیں جسم سے شک پڑ گیا کہ یہ جسم آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم کا نہیں.انہوں نے منہ پر سے کپڑا اٹھا کر دیکھا یا شایدمنہ ننگا تھا.بہرحال انہیں معلوم ہوا کہ سونے والے شخص حضرت علیؓ ہیں.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں.تب انہیں معلوم ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلامتی کے ساتھ جا چکے ہیں اور ان کے لئے اب سوائے ناکامی کے کچھ باقی نہیں رہا.غرض انہوں نے آپ کے قتل کا منصوبہ کیا مگر معجزانہ طور پر انہیں ناکام و نامراد ہونا پڑا.اس وقت یقیناً وہ لوگ جو کہتے تھے کہ انہیں قید کرو کہتے ہوں گے کہ ہم نہ کہتے تھے چوری قتل کا خیال چھوڑ دو باقاعدہ مکہ کی مجلس میں فیصلہ کر کے اسے قید کر دو یہ زیادہ اچھا ہے.تم نے ہماری بات نہ مانی اور یہ نتیجہ دیکھا.ضرور ہے کہ قتل کو ناپسند کرتے ہوئے اس کے کسی رشتہ دار نے انہیں خبر کر دی ہو گی اور وہ بچ نکلے.کچھ اور لوگ کہتے ہوںگے ہم نے جو کہا تھا اسے جلاوطن کر دو، قتل کا منصوبہ نہ کرو، تم نے ہمارے مشورہ کو ردّ کیا اور یہ دن دیکھا کہ سارے قبائل کو شرمندہ اور ناکام ہونا پڑا.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَمْكُرُوْنَ وَ يَمْكُرُ اللّٰهُ١ؕ وَ اللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ.وہ اگر یہ تدابیر کررہے تھے تو ہم بھی خاموش نہیں تھے ہم نے بھی فیصلہ کر دیا تھا کہ ایک ایک تدبیر میں ہم ان کفار کو ناکام کریں گے.چنانچہ قتل کی تدبیر کر کے انہوں نے دیکھ لیا وہ ناکام ہوئے.ان کی تدابیر سب باطل ثابت ہوئیں اور خدا تعالیٰ کا فیصلہ غالب آیا.یہ وہ فجر تھی جس کا دس تاریک راتوں کے بعد طلوع ہوا.اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ہجرت کی اجازت دے دی اور باوجود اس کے کہ کفار آپ کے دروازے پر قتل کے لئے کھڑے تھے آپ نے خدا تعالیٰ کی حفاظت میں مکہ کو چھوڑا اور مدینہ تشریف لے گئے اور یہ قتل کا منصوبہ آپ کو نقصان پہنچانے کی بجائے آپ کے لئے ایک معجزہ کے ظہور کا موجب ہوا.یہ پہلی خبر تھی جس سے مسلمانوں کے دل خوش ہوئے ورنہ ان کے دل کفار کے مظالم کو دیکھ دیکھ کر ہر وقت دکھتے رہتے تھے اور بسا اوقات وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم سے عرض بھی کرتے کہ یا رسول اللہ آپ یہاں سے ہجرت کر کے کہیں اور تشریف لے جائیں.مگر آپ یہی فرماتے کہ جب تک خدا تعالیٰ کا حکم نہ ملے میں اس بارہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا(صحیح البخاری کتاب مناقب الانصار باب ہجرۃ النبی صلی اللہ علیہوسلم ).لیکن کئی اور مسلمان ان راتوں کے مصائب سے تنگ آ کر مکہ چھوڑ کر چلے گئے بعض حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے اور بعض مدینہ منورہ میں چلے گئے اور گو ان کو حبشہ اور مدینہ میں آرام میسر آ گیا تھا اور کفار کے مظالم سے وہ بچ گئے تھے مگر ان کے دل ہروقت دُکھتے رہتے تھے کہ نہ معلوم ہمارا آقا کس حال میں ہو گا اور دشمن آپ سے کیا سلوک کر رہا ہوگا.جب رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم کی ہجرت کی خبر ان کو پہنچی تو وہ پہلی رات آرام کی نیند سوئے اور ان
Page 199
کے دل مطمئن ہوئے کہ اب ہمارا آقا دشمن کے حملوں سے محفوظ ہو گیا ہے.یہ ہجرت طلوع آفتاب کی ایک شعاع تھی جسے قرآن کریم میں فجر کے لفظ سے بیان کیا گیا تھا اور جو ظاہر کر رہی تھی کہ اب عنقریب کوئی آسمانی تغیّر ہونے والا ہے.اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ان دس راتوں کی فجر کے بعد شفع اور وتر کا بھی کوئی واقعہ ہوا ہے یا نہیں.اس غرض کے لئے جب ہم قرآن پر غور کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایک شفع اور وتر کے واقعہ کا بھی اس میں ذکر پایا جاتا ہے.اللہ تعالیٰ مدینہ کے کمزور مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے.اِلَّا تَنْصُرُوْهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّٰهُ اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ثَانِيَ اثْنَيْنِ اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُوْلُ لِصَاحِبِهٖ لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا١ۚ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلَيْهِ وَ اَيَّدَهٗ بِجُنُوْدٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَ جَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا السُّفْلٰى ١ؕ وَ كَلِمَةُ اللّٰهِ هِيَ الْعُلْيَا١ؕ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ(التوبۃ:۴۰) فرماتا ہے اگر تم ہمارے رسول کی مدد نہ کرو گے تو اس کا نقصان تمہیں خود ہی ہوگا.ہمارا رسول تو ہماری حفاظت میں ہے اور ہم خود اس کی ہر موقع پر نصرت اور تائید کرنے والے ہیں کیا تمہیں اس واقعہ کا علم نہیں جب کافروں نے اسے مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا اور جب وہ اکیلا نہیں بلکہ اپنے ساتھ ایک اور شخص کو لے کر مکہ میں سے نکلا اور غار میں آ کر چھپ گیا اور جب اس نے دیکھا کہ میرا ساتھی گھبرا رہا ہے اس لئے نہیں کہ اسے کوئی نقصان نہ پہنچ جائے بلکہ اس لئے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے تو اس نے اسے تسلی دی اور کہا لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا کہ غم مت کر ہم دو نہیں بلکہ ایک وتر بھی موجود ہے.وتر کی تشریح بھی خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی ہے چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ اِنَّ اللہَ وِتْرٌ یُـحِبُّ الْوِتْرَ.خدا تعالیٰ وتر ہے اور وتر کو ہی پسند کرتا ہے(سنن الترمذی ابواب الوتر باب ماجآء اَنَّ الْوِتْرَ لَیْسَ بِـحَتْمٍ) پس شفع کون تھا؟ شفع محمد صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم اور حضرت ابو بکرؓ تھے اور وتر کون تھا؟ وتر خدا تعالیٰ تھا جو ان دو کے ساتھ تھا.غرض خدا تعالیٰ نے یہ خبر دی تھی کہ اسلام اور مسلمانوں پر دس تاریک راتیں آئیں گی جن کے گذرنے پر ہم فجر کا طلوع کریں گے اور پھر اس فجر کے واقعہ کے ساتھ ہی ایک اور معجزہ دکھائیں گے جس کے ساتھ ایک شفع اور ایک وتر کا تعلق ہو گا یہ وہ معجزہ تھا جو غارِ ثور میں ظاہر ہوا اور جس نے وَيَمْكُرُوْنَ وَ يَمْكُرُ اللّٰهُ١ؕ وَ اللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ کی صداقت کو آفتاب نـصف النہار کی طرح روشن کر دیا.یہ امر بتایا جا چکا ہے کہ کفار نے ایک تدبیر یہ کی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر لیا جائے قتل کی تدبیر میں تو وہ ناکام ہو چکے تھے مگر جن لوگوں نے قید کا مشورہ دیا تھا
Page 200
وہ ضرور اپنے مشورہ پر فخر کرتے ہوں گے اور کہتے ہوں گے اگر قید کر لیتے تو یہ ناکامی تمہیں نہ دیکھنی پڑتی.اللہ تعالیٰ نے کہا بہت اچھا تم قید کر کے بھی دیکھ لو پھر بھی خدا تعالیٰ تمہیں ناکام کرے گا چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر ؓ دونوں جب مکہ میں سے نکلے تو غارثور میں جا کر چھپ گئے.کفار کو جب علم ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم کہیں باہر چلے گئے ہیں تو وہ تعاقب کرتے ہوئے غارثور کے منہ پر پہنچ گئے اور وہاں انہوں نے ڈیرہ ڈال دیا.کھوجی ان کے ساتھ تھا اس نے کہا کہ بس یہیں تک نشانات پہنچتے ہیں اب یا تو محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) یہیں کہیں چھپا ہوا ہے اور اگر یہاں نہیں تو پھر وہ آسمان پر چڑھ گیا ہے.عرب لوگ کھوجیوں کی بات پر بڑا اعتبار کیا کرتے تھے اور وہاں کے کھوجی اپنے فن میں بہت ماہر ہوا کرتے تھے.ہمارے ملک میں بھی ایسے کھوجی ہوتے ہیں جو بعض دفعہ چوری کا سراغ لگا لیتے ہیں مگر ہمارے کھوجی بہت ادنیٰ ہوتے ہیں.عرب کے کھوجی وہاں کے خاص حالات کے ماتحت بہت اعلیٰ درجہ کی مہارت رکھتے تھے چنانچہ وہ کھوجی جسے مکہ والے ساتھ لے گئے تھے اس نے صاف صاف کہہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ معلوم ہوتے ہیں.لوگوں نے کہا یہاں چھپنے کی کون سی جگہ ہے؟ اس نے کہا اگر یہاں نہیں ہیں تو پھر آسمان پر چلے گئے ہیں.اس کی یہ بات سن کر سب ہنسنے لگ گئے اور کہنے لگے کہ ہمارا کھوجی تو آج پاگل ہوگیا ہے کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے.بھلا یہ بھی کوئی چھپنے کی جگہ ہے اس غار کے منہ پر درخت کی شاخیں جھکی ہوئی ہیں اور ان پر مکڑی کا جالا بنا ہوا ہے اگر وہ اندر جاتے تو جالا نہ ٹوٹ جاتا یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نشان تھا جو اس نے دکھایا.مکڑی منٹوں میں جالا تن لیتی ہے میں نے خود اسے ایک بڑا جالا دو تین منٹ میں بُنتے ہوئے دیکھا ہے.اللہ تعالیٰ نے ایسا سامان کیا کہ مکڑی نے شاخوں پر جالا بُن دیا اور ان لوگوں کا ذہن ادھر نہ گیا کہ یہ جالا تھوڑی دیر میں بھی بنایا جا سکتا ہے.غرض کفار تو آپس میں یہ گفتگو کر رہے تھے اورادھر چند گز کے فاصلہ پر ابوبکرؓ غار ثور میں گھبرا رہے تھے اس لئے نہیں کہ ان کواپنی زندگی کو خطرہ تھا بلکہ اس لئے کہ انہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فکر لاحق ہوگیا تھا ورنہ یہ خیال درست نہیں کہ انہیں اس وجہ سے فکر ہوا کہ کہیں میں پکڑا نہ جاؤں.حدیثوں میں ذکر آتا ہے انہوں نے خود اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یارسول اللہ! اگر میں مارا گیا تو دنیا میں صرف ایک آدمی مارا جائے گا اس سے زیادہ میری موت کی کوئی اہمیت نہیں ہو گی لیکن یا رسول اللہ اگر آپ مارے گئے تو اسلام مارا جائے گا.جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو یہ گھبراہٹ پیدا ہوئی تو اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ’’لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا ‘‘
Page 201
غم مت کر خدا تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے(شــرح الــعــلامـۃ الـزرقـانی عـلی الـمـواھـب اللـدنیۃ جلد۱صفحہ ۲۳۶).رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ اِنَّ اللّٰہَ مَعِیَ.آپ نے یہ بھی نہیں کیا کہ صرف اتنا کہہ دیتے کہ لَاتَحْزَنْ فکر کی کوئی بات نہیں بلکہ آپ نے ابوبکرؓ کو اپنے ساتھ شامل کیا اور فرمایا خدا تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے.پس ثَانِيَ اثْنَيْنِ اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے سورۂ فجر کے اسی شفع اور وتر والے واقعہ کی طرف اشارہ کر دیا اور بتا دیا کہ وہ جو ہم نے خبر دی تھی کہ کوئی دو۲ ہوں گے اور تیسرا وتر ان کے ساتھ ہو گا وہ وعدہ ہم نے اس وقت پورا کر دیا تھا اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُوْلُ لِصَاحِبِهٖ لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا جب وہ دونوں غار میں چھپے بیٹھے تھے اور جب ہمارا رسول اپنے ساتھی سے یہ کہہ رہا تھا کہ غم مت کر.ہم صرف دو۲ نہیں بلکہ ایک خداجو وتر ہے ہمارے ساتھ ہے ورنہ ثَانِيَ اثْنَيْنِ کہنے کی اپنی ذات میں کوئی ضرورت نہیں تھی اس کے بغیر بھی یہ مضمون بیان ہو سکتا تھا کہ اگر تم مدد نہ کرو گے تو ہم اس کی مدد کریں گے.چنانچہ دیکھو غارثور میں ہم نے اس کی مدد کی یا نہیں.مضمون کو بیان کرنے کے لئے صرف اسی قدر ذکر کافی تھا ثَانِيَ اثْنَيْنِ اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی.لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ اس لئے استعمال فرمائے تا دنیا کو یہ بتائے کہ ہم نے وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ کہہ کر سورۂ فجر میں جو پیشگوئی کی تھی کہ طلوع فجر کے بعد یعنی مکہ سے ہجرت کرنے کے بعد ایک شفع اور وتر کا واقعہ ظاہر ہو گا وہ پیشگوئی ہماری پوری ہوچکی ہے فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلَيْهِ.جب وہ دو سے تین ہو گئے اور ابوبکرؓ کو پتہ لگا کہ ہم صرف دو نہیں بلکہ ایک تیسرا وتر بھی ہمارے ساتھ ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل پر سکینت نازل کی.وَاَيَّدَهٗ بِجُنُوْدٍ لَّمْ تَرَوْهَا.بادشاہ اکیلا نہیں ہوتا بلکہ لشکر اس کے ساتھ ہوتا ہے.محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عالم روحانی کے بادشاہ تھے اس لئے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے وہ لشکر بھیجے جن کو دنیا کے لوگ نہیں دیکھ سکتے تھے.وَ جَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا السُّفْلٰى.کفا ر نے کہا تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر لیا جاتا.اگر اس کو محبوس ومحصور کر لیا جاتا تویہ ناکامی نہ دیکھنی پڑتی.مگر خدا تعالیٰ نے اس تدبیر میں بھی ان کو ناکام کیا.باوجود اس کے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غارثور میں بند تھے کفار وہاں پہنچ چکے تھے پھر بھی کفار کا کلمہ ہی ذلیل ہوا.ان کو ہی ناکام ونامراد واپس لوٹنا پڑا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ اونچا ہوا.دیکھو یہ کتنا بڑا معجزہ ہے جو خدا تعالیٰ نے ظاہر کیا اور کتنا عظیم الشان نشان ہے جو اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ کفار نے تو یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کرکے ان کی آواز کو دبا دیں گے ان کے کلمہ کو نیچا کر دیں گے مگر خدا تعالیٰ نے اس قید کے نتیجہ میں ان کی آواز کو اور بھی اونچا کر دیا.وہ قید کر کے آپ کی آواز کو بند کرنا چاہتے تھے خدا تعالیٰ نے قید میں ڈال کر آپ کی آواز کو اور بھی بلند کر دیا اور اس قید کے واقعہ
Page 202
میں ایک ایسا معجزہ دکھایا جو قتل کے منصوبے کو ناکام کرنے والے معجزہ کی طرح ہمیشہ کے لئے اسلام کی صداقت اور رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم کے دعویٰ کے ثبوت میں پیش ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہے گا.اور غارثور کی قید محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذلّت کا موجب نہیں بلکہ ہمیشہ آپ کے کلمہ کے اعلاء کا موجب ہوتی رہے گی.دو۲ تدبیروں میں تو کفار کو ناکامی ہو چکی لیکن ابھی ایک تدبیر باقی تھی وہ لوگ جنہوں نے یہ مشورہ دیا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے باہر نکال دیا جائے کہہ سکتے تھے کہ ہمارے مشورے پر عمل نہ کیا گیا ورنہ اسلام کا خاتمہ ہو جاتا.خدا تعالیٰ نے نہ چاہا کہ یہ حسرت بھی ان کے دلوں میں باقی نہ رہ جائے وہ آپ کو صحیح سلامت مکہ سے مدینہ لے گیا اور اس طرح اس تیسرے گروہ کی بات بھی پوری ہو گئی کہ صحیح علاج یہ ہے کہ انہیں جلاوطن کر دیا جائے.جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو کفار نے اردگرد کے قبائل کو اکسانا اور بھڑکانا شروع کر دیا.کبھی خود چھاپے مارتے اور اس طرح مسلمانوں کو دق کرتے رہتے (سنن ابی داؤد کتاب الـخراج باب فی خبر نضیر) گویا ابھی ایک لیل مسلمانوں کے لئے باقی تھی.مدینہ میں مسلمانوں کویہ تسلی تو ہو گئی تھی کہ ہمارا رسول محفوظ ہو گیا ہے لیکن ابھی کفار کے مظالم بند نہ ہوئے تھے بلکہ نئے سرے سے انہوں نے عرب قبائل کو اسلام اور مسلمانوںکے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا تھا.اللہ تعالیٰ اسی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ گو دس راتوں کے گذرنے کے بعد روشنی کی ایک شعاع ظاہر ہو گئی ہے.ہجرت ہو چکی ہے اور شفع اور وتر کا واقعہ بھی رونما ہو چکا ہے مگر ابھی ایک رات باقی ہے.مشکلات کا ایک سال ابھی رہتا ہے اس ایک سال کے گذرنے کے بعد مسلمانوں کے لئے دوسری فجر چڑھا دی جائے گی.چنانچہ اس کا ذکر قرآن کریم میں یوں آتا ہے.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ وَ مَاۤ اَنْزَلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰنِ١ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.اِذْ اَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَ هُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوٰى وَ الرَّكْبُ اَسْفَلَ مِنْكُمْ١ؕ وَ لَوْ تَوَاعَدْتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيْعٰدِ١ۙ وَ لٰكِنْ لِّيَقْضِيَ اللّٰهُ اَمْرًا كَانَ مَفْعُوْلًا١ۙ۬ لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْۢ بَيِّنَةٍ وَّيَحْيٰى مَنْ حَيَّ عَنْۢ بَيِّنَةٍ١ؕ وَ اِنَّ اللّٰهَ لَسَمِيْعٌ عَلِيْمٌ.اِذْ يُرِيْكَهُمُ اللّٰهُ فِيْ مَنَامِكَ قَلِيْلًا١ؕ وَ لَوْ اَرٰىكَهُمْ كَثِيْرًا لَّفَشِلْتُمْ وَ لَتَنَازَعْتُمْ فِي الْاَمْرِ وَ لٰكِنَّ اللّٰهَ سَلَّمَ١ؕ اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ.وَ اِذْ يُرِيْكُمُوْهُمْ۠ اِذِ الْتَقَيْتُمْ فِيْۤ اَعْيُنِكُمْ قَلِيْلًا وَّ يُقَلِّلُكُمْ فِيْۤ اَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللّٰهُ اَمْرًا كَانَ مَفْعُوْلًا١ؕ وَ اِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ (الانفال:۴۲تا۴۵) ان آیات قرآنیہ میں جنگِ بدر کا تفصیل کے ساتھ ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اسے فرقان قرار دیا ہے اور بتایا ہے کہ اس جنگ کے ذریعہ ہم نے مسلمانوں کی مشکلات کا خاتمہ کر دیا.ان کی آخری رات
Page 203
کو بھی جو ان پر چھائی ہوئی تھی دور کر دیا اور ان کے لئے روشن صبح کا طلوع ہو گیا.یہ ایک عجیب بات ہے کہ وَالَّیْلِ اِذَا یَسْرِ میں رات کے جانے کی خبر دی گئی تھی جس کے معنے یہ تھے کہ اس ایک رات کے گذرنے پر فجر ظاہر ہو جائے گی.ادھر اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کا فرقان نام رکھا ہے اور فرقان کے متعلق لغت میں لکھا ہے کہ اس کے معنے ہیں اَلصُّبْحُ.اَلسَّحْرُ (اقرب ) پس وہ فتح کا دن جس کا وعدہ سورۂ فجر کی آیت وَالَّیْلِ اِذَا یَسْرِ میں کیا گیا تھا کہ طلوعِ فجر کے بعد بھی ایک گیارہویں رات ابھی باقی رہ جائے گی جو آخر دور کر دی جائے گی آخرکار اللہ تعالیٰ نے اس وعدہ کو جنگ بدر میں پورا کر دیا اور کفار کی طاقت کو اس نے ہمیشہ کے لئے توڑ کر رکھ دیا.اب کفار میں سے کوئی شخص بھی یہ کہنے کی طاقت نہیں رکھتا کہ اگر میرے مشورہ پر عمل کیا جاتا تو فائد ہ رہتا کیونکہ وہ تینوں تدابیر جو اسلام کو کچلنے کے لئے کی گئی تھیں اسلام اور مسلمانوں کی ترقی کا باعث بن گئیں.یہ ایک عجیب فجر تھی جو مسلمانوں کے لئے ظاہر ہوئی پہلی فجر تو وہ تھی جو دس راتوں کے بعد ظاہر ہوئی اور جس میں نور کی ایک شعاع مسلمانوں کو نظر آنے لگ گئی تھی مگر ابھی فجر کی صرف ایک لَوپیدا ہو ئی تھی کیونکہ ایک رات ابھی باقی تھی.جب وہ رات بھی گذر گئی اور گیارہ راتیں آ چکیں تو اللہ تعالیٰ نے یوم الفرقان ظاہر کر دیا جس میں عرب کی طاقت کو بالکل کچل دیا گیا.اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مسلمانوں پر اس کے بعد بھی مظالم ہوتے رہے اور انہیں کفار سے کئی لڑائیاں لڑنی پڑیں مگر اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ جنگ بدر نے کفار کی طاقت کو بالکل توڑ دیا تھا اور مسلمانوں کی شوکت ان پر ظاہر ہو گئی تھی.جنگ بدر جسے قرآن کریم نے فرقان قرار دیا ہے اس کے متعلق بائبل میں بھی پیشگوئی پائی جاتی ہے چنانچہ یسعیاہ باب ۲۱ آیت ۱۳تا۱۷ میں لکھا ہے ’’عرب کی بابت الہامی کلام.عرب کے صحرامیں تم رات کو کاٹو گے، اے دوانیوں کے قافلو، پانی لے کے پیاسے کا استقبال کرنے آؤ، اے تیما کی سرزمین کے باشندو، روٹی لے کے بھاگنے والے کے ملنے کو نکلو کیونکہ وَے تلواروں کے سامنے سے، ننگی تلوار سے اور کھینچی ہوئی کمان سے اور جنگ کی شدّت سے بھاگے ہیں کیونکہ خدا وند نے مجھ کو یوں فرمایا.ہنوز ایک برس ہاں مزدور کے سے ایک ٹھیک برس میں قیدار کی ساری حشمت جاتی رہے گی اور تیر اندازوں کے جو باقی رہے قیدار کے بہادر لوگ گھٹ جائیں گے کہ خداوند اسرائیل کے خدا نے یوں فرمایا.‘‘ (یسعیاہ باب ۲۱ آیت ۱۳تا۱۷) یسعیاہ نبی کے اس کلام میں یہ پیشگوئی کی گئی تھی کہ ہجرت کے زمانے پر ٹھیک ایک سال گذرنے کے بعد عرب
Page 204
میں ایک ایسی جنگ ہو گی جس میںقیدار کی ساری حشمت خاک میں مل جائے گی اور وہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھاگ جانے کا الزام لگاتے تھے اپنے لاؤ لشکر کی موجودگی میں پیٹھ دکھائیں گے اور وہ بھی ایسی حالت میں کہ کمانڈر اور ان کے جرنیلوں کی لاشیں میدان جنگ میں پڑی رہ جائیں گی.اور آخر وادئ مکہ اپنے جرنیلوں کو کھو کر اپنی اس شوکت کو بالکل کھو بیٹھے گی جو اس سے پہلے سے حاصل تھی.اسی طرح قرآن کریم نے ایک گیارھویں رات کی خبر دے کر یہ پیشگوئی کی تھی کہ ہجرت کے پورے ایک سال کے بعد کفار کی ساری طاقت ٹوٹ جائے گی اور مسلمانوں کے لئے فتح اور کامرانی کی صبح ظاہر ہو جائے گی.چنانچہ عین ایک سال کے بعد جنگ بدر ہوئی جس میں کفار کے بڑے بڑے لیڈر مارے گئے اور مسلمانوں کو ان پر نمایاں غلبہ حاصل ہوا.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کے لئے دعویٰ نبوت کے تیرھویں سال ربیع الاوّل کے مہینہ میں نکلے تھے(السیرۃ النبویۃ لابن ہشام زیرعنوان تاریـخ الھجرۃ) قاعدہ یہ ہے کہ سال کا بقیہ حصہ اسی سال میں شمار ہوتا ہے نئے سال میں شمار نہیں ہوتا اس لحاظ سے بقیہ چھ ماہ تیرہ سالہ مدت میں ہی شامل کرنے پڑیں گے.ورنہ دراصل مکہ میں مسلمانوں پر منظم حملوں کا عرصہ ساڑھے نو سال بنتا ہے.دسویں سال ربیع الاوّل میں آپ ہجرت کے لئے چل پڑے تھے مگر عام معروف قاعدہ کے مطابق بقیہ نصف سال اسی مکی زندگی کے تیرہ سالہ دَور میں شمار ہو گا اور نئے سال کا رمضان سے آغازسمجھا جائے گا.کیونکہ رمضان سے ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا سال شروع ہوتا ہے.اب دیکھ لو مدینہ میں آنے کے بعد پہلے رمضان تک اس پیشگوئی پر دس سال پورے ہوئے تھے اور رمضان سے گیارھویں سال کا آغاز ہوا تھا.اس ایک سال کے گذرنے پر دوسرے سال ۱۷؍رمضان کو بدر کی جنگ ہوئی (الکامل لابن اثیرزیر عنوان غزوۃ البدر الکبرٰی ) جس میں بڑے بڑے کفار مارے گئے اور ان کے ظالمانہ حملوں کا خاتمہ ہو گیا گویا وہ گیارہویں لَیْل جو مسلمانوں پر آئی ہوئی تھی ٹھیک ایک سال گذرنے کے بعد دور ہو گئی.اور مسلمانوں نے فتح و کامرانی کی صبح کو اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی تائید اور نصرت کے ساتھ دیکھ لیا.یہ ہے وہ مفہوم جو ان آیات قرآنیہ کا اللہ تعالیٰ نے مجھے سمجھایا اور جس کا ایک ایک ٹکڑہ اسلامی تاریخ اور قرآنی حوالوں سے ثابت ہے کوئی شخص اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ مسلمانوں پر دس تاریک راتیں آئیں اور پھر ان تاریک راتوں کے گذرنے پر ہجرت کی صورت میں فجر کی ایک شعاع ظاہر ہوئی اس کے بعد شفع اور وتر کا واقعہ ہوا اور آخر میں پھر ایک گیارہویں رات آئی جو اللہ تعالیٰ کے وعدہ کے مطابق پورے ایک سال کے بعد گذر گئی اور قیدار کی ساری حشمت خاک میں ملا دی گئی اس کے بعد بے شک جنگیں ہوئی ہیں مگر جنگِ بدرکے بعد کفار کا
Page 205
رعب بالکل مٹ گیا تھا اور اب وہ مسلمانوں کو ترنوالہ نہیں سمجھتے تھے بلکہ اس حقیقت کابر ملا اظہار کرتے تھے کہ مسلمانوں کا مقابلہ کرنا آسان بات نہیں.پس اس پیشگوئی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آئندہ حالات بیان کئے گئے ہیں اور وہ سارے واقعات جن کا اس جگہ پر ذکر ہے قرآن کریم میں نام لے لے کر بیان کر دیئے گئے ہیں بلکہ آخری تین حصے وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ.وَالَّیْلِ اِذَا یَسْرِ تو اکٹھے ایک ہی جگہ وَاِذْیَمْکُرُ بِکَ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا لِیُثْبِتُوْکَ اَوْ یَقْتُلُوْکَ اَوْیُخْرِجُوْکَ میں بیان کر دیئے گئے ہیں.میں اوپر بیان کر چکا ہوں کہ ترتیب تین قسم کی ہوتی ہے.ایک وہ ترتیب ہوتی ہے جس میں مضمون نیچے سے اوپر کو جاتا ہے.دوسری ترتیب وہ ہوتی جس میں مضمون اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے اور تیسری ترتیب مثلّث کی سی ہوتی ہے کہ چوٹی کی بات کو درمیان میں بیان کر دیا جاتا ہے اور اس سے چھوٹی باتوں کو دائیں بائیں رکھ دیا جاتا ہے.میں نے بتایا تھا کہ لِیُثْبِتُوْکَ اَوْ یَقْتُلُوْکَ اَوْیُخْرِجُوْکَ میں یہی مثلّث کی ترتیب پائی جاتی ہے کہ قتل جو سب سے اہم چیز تھی اس کا اللہ تعالیٰ نے درمیان میں ذکر کر دیا اور اثبات اور اخراج جو اس سے ادنیٰ درجہ کی چیزیں تھیں ان کو دائیں بائیں بیان کر دیا لیکن اس کے علاوہ مندرجہ بالا آیت میں ایک اور ترتیب بھی ہے جو سیدھی چلی جاتی ہے اور وہ یہ کہ اس جگہ کفار کے مشوروں کے لحاظ سے اثبات، قتل اور اخراج کا ذکر نہیں یعنی یہ مطلب نہیں کہ انہوں نے پہلے قید کا مشورہ کیا ہو پھر قتل کا اور سب سے آخر میں اخراج کا کیونکہ ان کا آخری فیصلہ قتل پر ہوا تھا نہ کہ اخراج پر.بلکہ ان امور کا ذکر وقوعہ کی ترتیب کے لحاظ سے ہوا ہے.مثلاً سب سے پہلے کفار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان پر گئے اور انہوں نے رات کے وقت اس کے اردگرد گھیرا ڈال لیا اور اپنے نقطۂ نگاہ سے انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم کو قید کر لیا.اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے اثبات یعنی قید کا ذکر پہلے فرمایا ہے اس کے بعد جب آپ ہجرت کے ارادہ سے اپنے مکان میں سے نکلے اور ان کے پاس سے گذرے تو ان کے لئے موقع تھا کہ وہ آپ کو قتل کر دیتے کیونکہ وہ اسی نیت اور اسی ارادہ کے ماتحت اکٹھے ہوئے تھے پس واقعات کے لحاظ سے چونکہ دوسرا نمبر قتل کے امکان کا تھا اس لئے اللہ تعالیٰ نے اثبات کے بعد قتل کا ذکر کر دیا اور بتایا کہ باوجود قتل کا ارادہ رکھنے کے وہ ناکام رہے اور آپؐکو قتل کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے.اس کے بعد اخراج کا واقعہ ہوا اور گو یہ ان کے مظالم کی وجہ سے ہی ہوا مگر جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ بیان فرمایا ہے کہ كَمَاۤ اَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْۢ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ(الانفال:۶) یعنی آپ کو نکالنے والا دراصل خدا تعالیٰ تھا.اس لئے کہ اگر آپ اس وقت نہ نکلتے تو
Page 206
دوسرے وقت آپ کی جان محفوظ نہ ہوتی.آپ گئے اور غارِ ثور میں پناہ گزیں ہو گئے اس وقت جب کفار تعاقب کرتے ہوئے غارثور تک پہنچے تو ان کا ارادہ یہی تھا کہ آپ کو ڈھونڈ کر نکالا جائے مگر آپ وہاں سے بھی بچ کر نکل گئے اور اس طرح اثبات، قتل اور اخراج تینوں تدابیر میں ان کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا.یہ دوسرے معنے دوسرے درجہ پر ہیں ورنہ میں ترجیح پہلے معنوں ہی کو دیتا ہوں.اب پیشتر اس کے میں اس پیشگوئی کے دوسرے ظہور کو بیان کروں ایک سوال کا جواب دے دیتا ہوں جو بعض لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو سکتا ہے اور وہ یہ کہ یہ معنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہی صحابہؓ پر کیوں نہ کھل گئے تاکہ اس زمانہ کے کفار پر حجت تمام ہو جاتی؟ سورۂ فجر کی پہلی چار آیات کی کی ہوئی تفسیر کے متعلق دو اعتراضات کا جواب اس سوال کے متعلق یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ جہاں تک حجت کا سوال ہے آج بھی ان معنوں کو پیش کر کے منکرین اسلام پر حجت تمام کی جا سکتی ہے اور انہیں اسلام اور قرآن کی صداقت کا قائل کیا جا سکتا ہے.قرآن کسی ایک زمانہ کے لئے نہیں بلکہ ہر زمانہ کے لئے ہے.آج دنیا میں جو لوگ اسلام کے مخالف پائے جاتے ہیں جو پیشگوئیوں کے قائل نہیں.جو اسلام کو جھوٹا مذہب تصور کرتے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا انکار کرتے ہیں ان کے سامنے بھی اگر ان پیشگوئیوں کو رکھا جائے تو یقیناً یہ پیشگوئیاں ان پر حجت ہوں گی اور اگر وہ انصاف اور دیانتداری سے کام لیں گے تو انہیں اسلام کی صداقت کا قائل ہونا پڑے گا.باقی رہا یہ سوال کہ یہ معنے پہلے کیوں نہ کھلے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہر زمانہ کے لحاظ سے مختلف قسم کے ہتھیار کام آیا کرتے ہیں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جو ہتھیار اس زمانہ میں کام آرہا ہو اس کے متعلق یہ اصول قرار دے دیا جائے کہ وہ پہلے زمانہ میں بھی ہونا چاہیے تھا.رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں آپ کی کامیابی اپنی ذات میں اتنا بڑا نشان تھا کہ صحابہؓ کو کسی اور طرف توجہ ہی نہیں ہوتی تھی چنانچہ تاریخی شواہد اس بارہ میں موجو د ہیں.جب مکہ فتح ہوا تو ہند (زوجہ ابوسفیان)کے خلاف سزا کا اعلان تھا.لیکن وہ چوری چھپے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئی اور آپ کی بیعت میں شامل ہو گئی.(السیرۃ الحلبیۃ ذکر فتح المکۃ) وہ چادر اوڑھ کر اور دوسری عورتوں میں شامل ہو کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کے لئے آگئی تھی بیعت لیتے لیتے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقعہ پر فرمایا کہ کہو ہم شرک نہیں کریں گی تو ہند (زوجہ ابوسفیان) اس کو برداشت نہ کر سکی اس کی طبیعت تیز تھی وہ فوراً بول اٹھی کہ یا رسول اللہ کیا ہم اب بھی شرک کریں گی.آپ اکیلے تھے اور ہم سب کے سب اکٹھے آپ کے مقابلہ میں کھڑے تھے اگر ان بتوں میں کوئی بھی طاقت ہوتی
Page 207
تو کیا یہ ممکن تھا کہ باوجود اس کے کہ ساری قوم ہمارے ساتھ تھی پھر بھی ہمیں ذلیل ہونا پڑتا اور آپ سب کے مقابلہ میں کامیاب ہو جاتے.آپ کی اس کامیابی کو دیکھنے کے بعد اب کوئی شخص شرک کر ہی کس طرح سکتا ہے کہ آپ یہ اقرار لے رہے ہیں کہ ہم شرک نہیں کریںگی.تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلبہ اور آپ کی کامیابی کا اس وقت اتنا اثر تھا کہ دوسری باتوں کی طرف لوگوں کی توجہ ہی نہ ہوتی تھی.قرآن کریم تو ہر زمانہ کے لئے ہے اور یہ لازمی بات ہے کہ جب وہ ہر زمانہ کے لئے ہے تو ہر زمانہ میں اس سے نئے سے نئے معارف نکلتے آئیں گے.یہی موٹی بات لے لو کہ شَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْۢ بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ (الاحقاف:۱۱) کے ماتحت بعد کے مفسرین تورات کی ان پیشگوئیوں کو بیان کرتے ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس میں موجود تھیں مگر خود صحابہؓ کا خیال اس طرف نہیں گیا (الفرقان فی تفسیر القرآن زیر آیت قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَ كَفَرْتُمْ بِهٖ وَشَهِدَ شَاهِدٌ).وہ سمجھتے تھے ہمیں گذشتہ پیشگوئیوں کی ضرورت نہیں ہمارے لئے یہی دلیل آپ کی سچائی کی کافی ہے کہ آپ اکیلے اٹھے، بےسروسامانی کی حالت میں اٹھے، مخالف حالات میں اٹھے اور پھر ساری دنیا پر غالب آگئے.لیکن جوں جوں زمانہ گذرتا گیا وہ نشان جو پہلے لوگوں کے دلوں کو مطمئن کر دیا کرتے تھے کافی نہ رہے اور ضرورت محسوس ہوئی کہ نئے نشانات کو قرآن کریم میں سے تلاش کیا جائے چنانچہ نئے نشانات تلاش کئے گئے اور پھر ان پر زیادہ زور دیا جاتا رہا.پس بات یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہؓ کو اس قسم کے دلائل کی ضرورت ہی نہیں تھی گو قرآن کریم میں ان کا ذکر موجود تھا لیکن چونکہ ہمیں اس بات کی ضرورت تھی کہ ہم اپنے زمانہ کے لوگوں کے لئے قرآن کریم میں سے نشانات تلاش کریں.اس لئے جب ہم نے اس نقطۂ نگاہ سے قرآن کریم پر غور کیا تو ہم پر نئے مطالب کھل گئے گویا پہلے لوگوں کے لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا ایک بیّن اور ظاہر اور واضح نشان یہ تھا کہ لوگوں نے آپ کو مارنا چاہا مگر مار نہ سکے، انہوں نے کچلنا چاہا مگر کچل نہ سکے، انہوں نے آپ کو مغلوب کرنا چاہا مگر آپ غالب آ گئے.اس عظیم الشان نشان کے بعد انہیں آپ کی صداقت کے متعلق کسی مزید دلیل کی ضرورت نہیں تھی.اسی طرح اسلام کی تعلیم یہودیت، مسیحیت،مجوسیت وغیرہ کے مقابلہ میں اتنی واضح اور اتنی شاندار تھی کہ وہ علیٰ وجہ البصیرت اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ جس قسم کے انصاف اور عدل اور محبت اور بدیوں سے بچنے کے احکام اسلام میں پائے جاتے ہیں اور کسی مذہب میں نہیں پائے جاتے اس لئے وہ ضرورت ہی نہیں سمجھتے تھے کہ اور باتوں کی طرف توجہ کریں یا اسلام کی صداقت کے متعلق گذشتہ مذاہب کی پیشگوئیوں کو تلاش کریں.مفسرین نے یہ پیشگوئیاں لکھی ہیں مگر اسی وقت جب اسلام عیسائی ممالک میں پہنچا چونکہ اس وقت وہ
Page 208
دلائل جو مشرکین کے لئے بیان کئے جاتے تھے عیسائیوں کے لئے کافی نہیں تھے اس لئے انہوں نے کتبِ صادقہ سے پیشگوئیاں تلاش کرنی شروع کر دیں.اسی طرح قرآن کریم پر غور کر کے انہوں نے نئے نئے دلائل پیدا کئے چنانچہ بعد کی تفسیروںمیں جو کچھ لکھا گیا ہے وہ اسی ضرورت کے ماتحت ظاہر ہوا ہے.بے شک کان موجود تھی مگر پہلے جس چیز کی ضرورت نہیں تھی وہ حکمت الٰہی کے ماتحت پوشیدہ رہی اور اس وقت ظاہر ہوئی جب زمانہ کو اس کی ضرورت تھی.علوم کی ترقی میں ہمیشہ ایک قدم کے بعد دوسرا قدم اٹھتا ہے اور وہ دوسرا قدم ہمیشہ آگے کی طرف اٹھتا ہے.پیچھے کی طرف نہیں جاتا.ایک ماں بچے کو اٹھا کر دس میل چلتی ہے لیکن باجود اس کے کہ ماں طاقتور ہوتی ہے اور بچہ کمزور، ماں کے پاؤں میں چلتے چلتے چھالے پڑ جاتے ہیں پھر بھی اگر دس میل کے بعد بچہ دو قدم بھی چلے گا تو آگے ہی جائے گا پیچھے نہیں جائے گا.لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ماں سے بڑھ گیا.اسی طرح بعض دفعہ کم علم والاپہلوں سے زیادہ دلائل اخذ کر لیتا ہے کیونکہ علم ہمیشہ بڑھتا رہتا ہے اور قرآن کریم میں سے نئے سے نئے معارف ہر زمانہ کی ضرورت کے مطابق نکلتے رہتے ہیں.پس یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام پر یہ معنے کیوں کھلے.یہ سوال بھی بعض لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو سکتا ہے کہ لَیَالٍ عَشْرٍ کو نکرہ کے طور پر کیوں بیان کیا گیا ہے یہ بحث ایسی ہے جو پرانے مفسرین نے بھی اٹھائی ہے کہ یہاں وَلَیَالٍ عَشْرٍ کی بجائے وَاللَّیَالِی الْعَشْـرِ کہنا چاہیے تھا اسے نکرہ کیوں بیان کیا ہے.اس کا جواب انہوں نے یہ دیا ہے کہ جو بالکل درست ہے کہ خدا تعالیٰ نے اسے نکرہ کے طورپر اس لئے بیان کیا ہے تاکہ ان لیالی کی عظمت کی طرف اشارہ کیا جائے.عربی زبان میں تنوین کئی اغراض کے لئے آتی ہے.بعض دفعہ تنوین تنکیر کے لئے استعمال کی جاتی ہے اور بعض دفعہ کسی چیز کی عظمت بیان کرنے کے لئے.عظمت سے یہ مراد نہیں کہ وہ چیز ضرور اچھی ہو بلکہ اچھی یا بری جس شق میں بھی کوئی چیز بڑی ہو اس کے لئے تنوین آ جائے گی.مثلاً ظلم بڑا ہو یا انعام بڑا ہو تو دونوں کا تنوین سے ذکر کیا جائے گا(تفسیر الکشاف زیر آیت وَلَیَالٍ عَشْرٍ).انہوں نے رمضان یا ذی الحجہ کی راتیں اس سے مراد لی ہیں کیونکہ وہ بڑی عظمت اور شان رکھنے والی ہیں لیکن جیسا کہ میں ثابت کر چکا ہوں اس سے یہ مراد نہیں بلکہ اس سے ظلم کے وہ دس مکی سال مراد ہیں جن کا احادیث سے بھی پتہ لگتا ہے اور تاریخ بھی گواہ ہے ان دس سالوں میں مسلمانوں پر بڑے بڑے مظالم کئے گئے اور انہیں طرح طرح کے دکھ دیئے گئے یہاں تک کہ دو دفعہ صحابہؓ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے اور ایک دفعہ انہوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی.گویا علاقوں کے لحاظ سے دو اور تعداد کے لحاظ سے تین ہجرتیں انہیں کرنی پڑیں.پس چونکہ ان دس راتوں میںکفار مکہ کی طرف سے مسلمانوں پر شدید مظالم ہونے والے تھے اس لئے ان
Page 209
کا نکرہ کے طور پر ذکر کیا گیا یہ بتانے کے لئے کہ ان میں انتہا درجہ کا ظلم ہو گا.موجودہ زمانہ کے متعلق پیشگوئی میں نے بتایا تھا کہ گذشتہ کئی سورتوں میں اکٹھی پیشگوئیاں چل رہی ہیں.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثتِ اولیٰ کے متعلق بھی اور آپ کی بعثتِ ثانیہ کے متعلق بھی.سورۃ الفجر بھی اسی سلسلہ کی ایک اہم کڑی ہے اور جس طرح سورۂ غاشیہ اور بعض دوسری سورتوں میں اکٹھے حالات بیان کئے گئے ہیں.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثتِ اولیٰ کے بھی اور آپ کی بعثتِ ثانیہ کے بھی.اسی طرح اس سورۃ میں دونوں زمانوں کے حالات اکٹھے بیان کر دیئے گئے ہیں.پس یہ پیشگوئی صرف ایک زمانہ کے متعلق نہیں بلکہ دو۲ زمانوں کے متعلق ہے اور اس زمانہ کا پتہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم کی اخبار سے بھی ملتا ہے اور قرآن کریم کی آیت الٓمّٓرٰ١۫ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ١ؕ وَ الَّذِيْۤ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ الْحَقُّ وَ لٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُوْنَ (الرعد:۲) میں بھی اس کے متعلق اشارہ پایا جاتا ہے.ابن اسحاق نے اور بخاری نے اپنی تاریخ میں نیز ابن جریر نے ابن عباس سے اور انہوں نے جابر بن عبداللہ سے روایت کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سورۂ بقرہ کی ابتدائی آیات تلاوت کر رہے تھے کہ ایک یہودی ابو یاسر اپنے ساتھیوں سمیت آپ کے پاس سے گذرا اور اس نے سورۂ بقرہ کی ان آیا ت کو سنا.وہ یہود کے علماء میں سے تھا ان آیات کو سنتے ہی وہ سیدھا گھر کی طرف روانہ ہوا تا کہ وہ اپنے بھائی حُییی بن اخطب کو یہ واقعہ بتائے.تب اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ یہ یہ آیتیں میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہیں اس نے کہا کہ کیا تم نے خود اپنے کانوں سے سنی ہیں یا کسی اور شخص سے؟ وہ کہنے لگا میں نے اپنے کانوں سے یہ آیتیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے سنا ہے.اس نے کہا اچھا تم ابھی میرے ساتھ چلو.چنانچہ وہ سب کے سب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے اور حُییی نے عرض کیا کہ میرا بھائی کہتا ہے کہ یہ یہ آیتیں آپ کو الہام ہوئی ہیں میں یہ دریافت کرنے آیا ہوں کہ کیا یہ درست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ آیات نازل کی ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ آیتیں مجھ پر اللہ تعالیٰ نے ہی نازل کی ہیں.انہوں نے کہا اگر یہ بات ہے تو پھر معاملہ آسان ہو گیا آپ کا الہام ہے الٓمّٓ.سو ابجد کے لحاظ سے الف کا ایک لام کے ۳۰ میم کے ۴۰ کل ۷۱ سال بنے بالفرض اگر آپ کو غلبہ بھی ہوا تو صرف ۷۱ سال رہے گا.اس عرصہ میں اگر ہمیں آپ کی غلامی
Page 210
کرنی پڑی تو معمولی بات ہے ۷۱ سال تک ہم تکلیفیں برداشت کر لیں گے اس کے بعد آپ کا غلبہ نہیں رہ سکتا.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ایک اور الہام بھی ہوا ہے.انہوں نے کہا.کیا؟ آپ نے فرمایا الٓمّٓصٓ وہ کہنے لگے تو پھر بھی کیا ہوا.الف کا ایک لام کے ۳۰ میم کے ۴۰ ص کے ۹۰ کل ۱۶۱ سال بنے یہ بھی کوئی بڑی مدت نہیں.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے الٓرٰ بھی الہام ہوا ہے.یہ سن کر وہ پھر حساب لگانے لگے اور کہا کہ الف کا ایک لام کے ۳۰ ر کے ۲۰۰ کل ۲۳۱ سال بنے یہ بھی کوئی زیادہ معیاد نہیں ہے.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے الٓمّٓرٰ بھی الہام ہوا ہے یہ سن کر وہ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے کہ چلو یہاں سے یہ معاملہ تو کچھ مشتبہ ہو گیا ہے(فتح البیان زیر آیت الٓمّٓ) اس حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تردید نہیں کی بلکہ ان کی باتوں کی تصدیق کرتے چلے گئے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حروف مقطعات میں علاوہ دوسری باتوں کے ایک یہ بات بھی پائی جاتی ہے کہ ان میں بعض ایسے واقعات کا بطور پیشگوئی ذکر ہے جو اسلام کو پیش آنے والے تھے خواہ وہ اچھے تھے یا برے.چنانچہ ہم دیکھتے ہیں سورۂ رعد جو نہایت خطرناک خبروں پر مشتمل ہے اس کی ابتدا الٓمّٓرٰ سے کی گئی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کی ترقی کا زمانہ ۲۷۱ سال تک جانے والا تھا اور ۲۷۱ ھ سے اسلام میں کوئی خاص تنزل واقعہ ہونے والا تھا کیونکہ الٓمّٓرٰ کے اعداد ابجد کے لحاظ سے ۲۷۱ہیں.الف کا ایک لام کے ۳۰ م کے ۴۰ ر کے ۲۰۰
Page 211
مسلمانوں کے تنزّل کی تاریخ چنانچہ میں نے جب اس حدیث کو دیکھا اور سورۂ رعد پر بھی غور کیا تو میں نے یہ تحقیق شروع کی کہ آیا ۲۷۱ھ میں یا اس کے قریب قریب کوئی خاص اور اہم واقعہ جس کا تعلق اسلامی تنزل کے ساتھ ہو رونما ہوا ہے یا نہیں کیونکہ بعض دفعہ کوئی واقعہ رونما تو کسی سال ہوتا ہے مگر اس کی بنیاد ایک ایک دو دو سال پہلے سے پڑنی شروع ہو جاتی ہے اس لحاظ سے میں نے غور کیا کہ آیا۲۷۰ھ سے ۲۸۰ھ تک کوئی واقعہ ایسا ہوا ہے یا نہیں جسے اسلامی تنزل کی بنیاد قرار دیا جا سکے.جب میں نے غور کیا اور اسلامی تاریخ کو دیکھا تو میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب ۲۷۰ھ یا۲۷۲ھ یا ۲۷۳ھ یا ۲۷۴ھ میں نہیں بلکہ عین ۲۷۱ھ میں سپین کے بادشاہ نے پوپ سے معاہدہ کیا کہ وہ بغدادی حکومت کو تباہ کرنے کے لئے اس کا ساتھ دے گا.گویا ایک مسلمان بادشاہ نے ایک عیسائی بادشاہ سے معاہدہ کیا کہ وہ اس کے ساتھ مل کر اسلامی بادشاہ کا مقابلہ کرے گا اور اس کی حکومت کو تباہ کرے گا.اس کے بعد بغداد رہ گیا تھا میں نے اس کی تاریخ کا مطالعہ کیا تو معلوم ہوا کہ ۲۷۲ھ یا۲۷۳ھ میں بغداد کی حکومت نے قیصر روم سے معاہدہ کیا کہ وہ اس کے ساتھ مل کر سپین کی حکومت کو تباہ کرے گا.یہ دو۲ واقعات ایسے خطرناک ہوئے جنہوں نے اسلام کی طاقت کو ہمیشہ کے لئے کمزور کر دیا اور اسلامی ترقی کا دَور اپنی شان اور عظمت کو کھو بیٹھا.اس سے پہلے مسلمانوں کے اتحاد کی یہ حالت تھی کہ قیصر روم نے جب حضرت علیؓ اور معاویہ کو آپس میں جنگ کرتے دیکھا تو اس نے ارادہ کیا کہ میں مسلمانوں پر حملہ کر دوں.چونکہ رستہ میں معاویہ کی حکومت تھی اور بعد میں حضرت علیؓ کی حکومت آتی تھی.اس لئے جب حضرت معاویہ نے یہ بات سنی تو انہوں نے قیصر روم کو کہلا بھیجا کہ ہماری آپس کی لڑائی سے تمہیں کسی غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے یاد رکھو اگر تمہارا لشکر آیا تو سب سے پہلا جرنیل جو علیؓ کی طرف سے تمہارے مقابلہ کے لئے نکلے گا وہ میں ہوں گا(البدایۃ النـھایۃ جلد ۸ صفحہ ۱۲۵،۱۲۶) یعنی صرف یہی نہیں کہ سب سے پہلے میں تمہارے ساتھ لڑوں گا بلکہ اسی وقت میں اپنے ہتھیار ڈال دوں گا اور علیؓ کے ماتحت ہو جاؤں گا.قیصر روم نے جب یہ بات سنی تو وہ ڈر گیا اور اس نے مسلمانوں پر حملے کا ارادہ ترک کر دیا.اب یا تو مسلمانوں کی یہ حالت تھی کہ وہ باوجود آپس میں برسرِ پیکار ہونے کے دشمن کے مقابلہ میں متحد ہو جاتے تھے اور یا یہ زمانہ آیا کہ ۲۷۱ھ میں ایک اسلامی حکومت پاپائے روم سے اور دوسری اسلامی حکومت قیصر قسطنطنیہ سے اس لئے معاہدہ کرتی ہے کہ دوسری اسلامی حکومت کو وہ عیسائیوں کے ساتھ مل کر مٹا دے اور اس کی طاقت کو کچل دے.اِنَّا لِلّٰهِ وَ اِنَّاۤ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ.گویا انتہا درجہ کے تنزل کی بنیاد
Page 212
۲۷۱ھ میں پڑی.تب میں نے سمجھا کہ وہ نظریہ جو یہود کا تھا اور جس کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تردید نہیں کی تھی وہ اپنے اندر حقیقت رکھتا تھا.اسلام کے دوبارہ احیاء کی تاریخ کی تعیین پھر ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے يُدَبِّرُ الْاَمْرَ مِنَ السَّمَآءِ اِلَى الْاَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ اِلَيْهِ فِيْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗۤ اَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ (السجدۃ:۶) جس طرح خدا تعالیٰ کی ہمیشہ سے یہ سنّت چلی آئی ہے کہ وہ آسمان سے لوگوں کی ہدایت کا انتظام کر کے اسے دنیا میں بھیجتا اور اپنا ایک سلسلہ قائم فرماتا ہے اسی طرح وہ اب بھی کرے گا اور اسلام کو دنیا میں قائم کر دے گا مگر پھر وہ سلسلہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ قائم ہو گا آسمان پر اٹھنا شروع ہو گا ایک ایسے دن میں جو ہزار سال کے برابر ہو گا.اس آیت میں تنزلِ اسلام کے ایک ہزار سالہ دَور کی خبر دی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ اس دوران میں ایمان اور اسلام آسمان پر اٹھ جائے گا اور لوگوں میں بے دینی پھیل جائے گی.پس ان پہلے معنوں کے رُو سے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے اعتبار سے کئے گئے ہیں لَیْل سے مراد ایک سال کا عرصہ تھا مگر دوسرے معنوں کے رُو سے لَیْل سے مراد ایک صدی ہے اور بتایا گیا ہے کہ اسلام پر دس تاریک راتیں آئیں گی جن میں سے ہررات ایک ایک سو سال کی ہو گی اور یہ سلسلہ برابر دس راتوں یعنی ایک ہزار سال تک چلتا چلا جائے گا.دیکھو یہ کیسی لطیف مشابہت ہے کہ جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تین سال کے بعد ظلم وتعدّی کا ایک دَور آیا جو دس سال تک چلتا چلا گیا اسی طرح یہاں تین صدیوں کے بعد ایک اسلامی تنزّل کے دَور کی خبر دی گئی اور بتایا گیا کہ وہ دَور دس صدیوں یعنی ایک ہزار سال تک چلا جائے گا اور چونکہ یہ دَور ۲۷۱ھ سال سے شروع ہوا ہے اس لئے ایک ہزار سال میں اگر ان ۲۷۱ھ سالوں کو ملایا جائے تو یہ ۱۲۷۱ سال بن جاتے ہیں یعنی قریباً تیرہ صدیاں.پس تیرہ سو سال کے ایک زمانہ کا ذکر قرآن کریم سے ثابت ہو گیا جن میں سے ۲۷۱سال یا قریباً تین صدیاں اسلامی ترقی کی ہیں اور دس سو سال رات سے مشابہت رکھتے ہیں.پھر جس طرح وہاں دس راتوں کے بعد ایک فجر کے طلوع کی بشارت دی گئی تھی اسی طرح قرآن کریم میں ان دس تاریک راتوں کے بعد جن میں سے ہر رات سو۱۰۰ سو۱۰۰ سال کی بتائی گئی ہے.ایک فجر کے ظاہر ہونے کی بھی خبر دی گئی ہے اسی مضمون کی طرف سورۂ سبا کی اس آیت میں اشارہ کیا گیا ہے کہ وَ مَاۤ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّ نَذِيْرًا وَّ لٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ.وَ يَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ.قُلْ لَّكُمْ مِّيْعَادُ يَوْمٍ لَّا تَسْتَاْخِرُوْنَ۠ عَنْهُ سَاعَةً وَّ لَا تَسْتَقْدِمُوْنَ۠(سبا:۲۹تا۳۱)
Page 213
اس آیت کی تشریح سے پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ سورۂ احزاب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم کے خاتم النبیّین ہونے کا دعویٰ لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا تھا اور بتایا گیا تھا کہ آئندہ تمام فیوض رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ سے ہی بنی نوع انسان حاصل کر سکیں گے براہ راست بغیر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں کر سکتے.یہ مضمون جو سورۂ احزاب میں تھا اسی کا سورۂ سبا میں ذکر آتا ہے اور اس امر کا ثبوت دیا گیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ دنیا میں ایک مستقل نظام قائم کیا جائے گا.خاتم کے معنے یہ تھے کہ آپ سے الگ ہوکر کوئی فیضان نہیں ملے گا بلکہ آپ کی اطاعت اور غلامی میں رہ کر انسان الٰہی برکات اور فیوض سے متمتع ہو سکے گا.اس پر سوال پیدا ہوتا تھا کہ کیااس کے یہ معنے ہیں کہ نظامِ روحانی میں آپ نے لوگوں کو اعلیٰ مقامات کے حصول سے روک دیا ہے؟ اس کا جواب سورۂ سبا میں اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ آپ نے نظام روحانی میں لوگوں کو اعلیٰ مقامات کے حصول سے نہیں روکا اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہمیشہ ایسے نبی آتے رہیں گے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم کے خدام اور آپؐکے غلاموں میں سے ہوں گے چنانچہ فرمایا اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیری نبوت ختم ہونے والی نہیں بلکہ قیامت تک جاری رہے گی.اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ تو قیامت تک لوگوں کے لئے بشیر و نذیر ہے جیسے کہ فرمایا وَ مَاۤ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّ نَذِيْرًا (سبا:۲۹)ہم نے تجھے تمام انسانوں کے لئے خواہ وہ عرب ہوں، شامی ہوں، فلسطینی ہوں یا اور کسی قوم کے ہوں.اس صدی کے ہوں یا اگلی صدی کے سب کے لئے بشیر ونذیر بنا کر بھیجا ہے.یوں تو ہر نبی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھڑا ہو اس کو ماننا پڑتا ہے.موسیٰ علیہ السلام گو ساری دنیا کے لئے مامور نہیں تھے مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والوں کو ان پر بھی ایمان لانا پڑتا ہے لیکن فرماتا ہے ہم نے تجھے خالی اس لئے نہیں بھیجا کہ لوگ تجھ پر ایمان لائیں بلکہ تو قیامت تک ہر زمانہ میں بشیر و نذیر ہو گا.موسٰی بے شک نبی ہیں مگر وہ آج کوئی بشارت اور انذار نہیں کرر ہے ان کے کوئی ایسے احکام نہیں چل رہے جن کے انکار کی وجہ سے لوگوں پر عذاب نازل ہو یا جن کو ماننے کی وجہ سے وہ خدا تعالیٰ کے فضل اور اس کے انعامات کے مورد ہوں.ماننے کی وجہ سے فضل نازل ہونا اور انکار پر عذاب نازل ہونا اسی نبی کی وجہ سے ہوتا ہے جس کی نبوت جاری ہو.پس فرماتا ہے ہم نے تجھے تمام لوگوں کے لئے اور تمام زمانوں کے لئے مبعوث فرمایا ہے ایسی صورت میں کہ صرف تیری نبوت پر ان کے لئے ایمان لانا ضروری نہیں بلکہ تو ان کے لئے بشیر ونذیر بھی ہو گا.جو لوگ تجھے مانیں گے ان پر خدا تعالیٰ کے فضل نازل ہوں گے اور جو انکار کریں گے ان پر خدا تعالیٰ کا عذاب نازل ہو گا.پھر فرماتا ہے وَلٰکِنَّ اَکْثَرَ النَّاسِ لَا یَعْلَمُوْنَ (سبا:۲۹) لیکن اکثر لوگ اس سے واقف
Page 214
نہیں.اس سے یہ مراد نہیں ہو سکتی کہ لوگ ایمان نہیں لا رہے کیونکہ یہ تو صاف بات ہے کہ وہ ایمان نہیں لا رہے تھے اس کے ذکر کا کوئی خاص فائدہ نہیں تھا اس کے معنے درحقیقت یہ ہیں کہ ہم نے یہ ایک ایسی بات کہی ہے جس سے لوگ پہلے واقف نہیں تھے.پہلے لوگ صرف قومی اور وقتی نبیوں کے قائل تھے سوائے عیسائیوں کے ایک فرقہ کے جو ساری دنیا کے لئے اور ہمیشہ کے لئے روحانی بادشاہت کا قائل تھا.لیکن باقی لوگوں میں سے کوئی بھی اس کا قائل نہیں تھا.کیونکہ نبی آتے رہے اور ان کی تعلیمیں منسوخ ہوتی رہیں.پس فرمایا کہ ہم تیرے متعلق ایک ایسا دعویٰ کر رہے ہیں جس سے لوگ واقف نہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ایک نبی کے بعد جب بھی دوسرا نبی آتا ہے وہ پہلے نبی کی نبوت کو منسوخ کر دیتا ہے.ساری دنیا کی طرف ایک نبی کا ہونا اور پھر ہر زمانہ کے لئے ہونا یہ دو۲ باتیں پہلے کسی نبی میں جمع نہیں ہوئیں.ہندو وید کو ہمیشہ کے لئے مانتے ہیں.مگر وہ ساری دنیا کے لئے نہیں مانتے.شودروں کے متعلق کہتے ہیں کہ اگر وہ ویدوں کو سن لیں تو سیسہ پگھلا کر ان کے کان میں ڈالا جائے.زرتشتی خاموش ہیں.مگر اتنی بات بالکل واضح ہے کہ ان کا مذہب ساری دنیا کے لئے نہیں.یہودی ہیں وہ گو اب کہتے ہیں کہ ان کی شریعت ہمیشہ کے لئے ہے.مگر یہ خیال آخری زمانہ میں ان میں پیدا ہوا ہے.پہلے ان کا یہی خیال تھا کہ ایک اور شریعت آنے والی ہے.جیسا کہ استثنا ۱۸/۱۸ اور ۳۳/۲سے ظاہر ہے.اس کے بعد حضرت عیسٰی علیہ السلام آئے وہ بھی ساری دنیا کے لئے نہیں تھے.مگر چونکہ وہ ایک ایسے زمانہ میں آئے ہیں جب وہ وقت بالکل قریب آ رہا تھا جب کہ ساری دنیا کے لئے ایک نبی بھیجا جائے اور حالات میں جلد جلد تغیّر پیدا ہو رہا تھا اس لئے عیسائیوں نے غلطی سے حضرت عیسٰی علیہ السلام کے متعلق یہ سمجھ لیا کہ وہی تمام دنیا کے لئے بھیجے گئے ہیں.لیکن عیسائی اَکْثَرَ النَّاسِ نہیں ہیں اور خدا تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ وَلٰکِنَّ اَکْثَرَ النَّاسِ لَا یَعْلَمُوْنَ (سبا:۲۹) یعنی دنیا کا اکثر حصہ ایسا ہے جو اس عقیدے کا قائل ہی نہیں.وہ یہ مانتا ہی نہیں کہ ساری دنیا کے لئے شریعت ہو اور پھر وہ شریعت ہمیشہ کے لئے ہو.یہ دونوں فرق چلتے چلے جاتے ہیں اور سوائے عیسائیوں کے دنیا میں جس قدر مذاہب پائے جاتے ہیں ان میں سے اکثر اس کے قائل نہیں.اور جو لوگ قائل ہیں وہ بہت ہی تھوڑے ہیں.اس کے بعد فرماتا ہے وَ يَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ(سبا:۳۰).یعنی وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ جب یہ کہا گیا کہ آنحضرتؐہر زمانہ کے لئے ہیں اور ہر زمانہ کے لئے وہ بشیر اور نذیر ہیں تو اس کے معنے یہ ہیں کہ پھر بھی ایسے زمانے آتے رہیں گے جب دنیا میں خرابی پیدا ہو گی اور آنحضرتؐبحیثیت بشیر اور نذیر کے دنیا میںظاہر ہوں گے.ہمارا سوال یہ ہے کہ ایسا زمانہ کب آئے گا اور کب بحیثیت بشیر اور نذیر کے آنحضرتؐدنیا میں ظاہر ہوں گے.
Page 215
یہ امر ظاہر ہے کہ قیامت تک بشیر و نذیر ہونے کے یہ معنے تو نہیں ہو سکتے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر زمانہ میں اپنے جسد ِعنصری کے ساتھ واپس آئیں گے اور تبشیر وانذار کا کام سرانجام دیں گے بلکہ اس کے معنے یہ تھے کہ آپؐکے اظلال دنیا میں پیدا ہوتے رہیں گے اور جب بھی کوئی خرابی واقع ہو گی آپؐکے اظلال بشیر و نذیر بن کر کھڑے ہو جائیں گے اور اس طرح برابر آپؐکا وجود دنیا میں ظاہر ہوتا رہے گا.اللہ تعالیٰ یہی جواب اس موقع پر پیش کرتا ہے اور فرماتا ہے قُلْ لَّكُمْ مِّيْعَادُ يَوْمٍ لَّا تَسْتَاْخِرُوْنَ۠ عَنْهُ سَاعَةً وَّ لَا تَسْتَقْدِمُوْنَ۠(سبا:۳۰)ہم اس کے لئے ایک دن کی معیاد سورۂ سجدہ میں مقرر کر چکے ہیں.یعنی ایک ہزار سالہ خرابی کا دَور گذرنے کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہو گا.اور آپؐدوبارہ بشیر و نذیر بن کر دنیا میں آ جائیں گے.پس قُلْ لَّكُمْ مِّيْعَادُ يَوْمٍ لَّا تَسْتَاْخِرُوْنَ۠ عَنْهُ سَاعَةً وَّ لَا تَسْتَقْدِمُوْنَ۠ میں انہی دس تاریک راتوں کی طرف اشارہ ہے جو اسلام کے قریبًا تین سو سالہ دَور ترقی کے بعد مسلمانوں پر آئیں جو ایک ہزار سال تک ممتد چلی گئیں اور جن کا ذکر سورۂ سجدہ میں ان الفاظ میں پایا جاتا ہے کہ يُدَبِّرُ الْاَمْرَ مِنَ السَّمَآءِ اِلَى الْاَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ اِلَيْهِ فِيْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗۤ اَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ.غرض تیرہ سو سال کے ایک زمانہ کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے جن میں سے دس سو سال کے متعلق بتایا گیا ہے کہ وہ رات کے مشابہ ہوں گے اور ہر رات ایک ایک سو سال کی ہو گی اور اس طرح دس راتیں یکے بعد دیگرے مسلمانوں پر آئیں گی.اسی طرح قرآن کریم میں آتا ہےفَلَاۤ اُقْسِمُ بِالشَّفَقِ.وَ الَّيْلِ وَ مَا وَسَقَ.وَ الْقَمَرِ اِذَا اتَّسَقَ.لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ(الانشقاق:۱۷تا۲۰) جس طرح تم کہتے ہو اس طرح نہیں بلکہ میں شہادت کے طور پر پیش کرتا ہوں شفق کو.پھر میں شہادت کے طور پر پیش کرتا ہوں رات کو اور اس کو جسے وہ اپنے اندر جمع کر لیتی ہے اور پھر میں شہادت کے طور پر پیش کرتا ہوں چاند کو جب وہ تیرھویں رات کا ہو جاتا ہے.اِتِّسَاق کے معنے ہوتے ہیں تیرھویں رات کا چاند.پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَاۤ اُقْسِمُ بِالشَّفَقِیہ بات نہیں جو تم کہتے ہو.میں شہادت کے طور پر شفق کو پیش کرتا ہوں جب سورج تو ڈوب جاتا ہے لیکن اس کی سرخی رہ جاتی ہے.اس میں کفّار کو بتایا کہ اس وقت اسلام کو مغلوب کرنے کی کوششیں بالکل عبث ہیں اسلام غالب آئے گا اور تم اس کے مقابلہ میں خواہ کتنی کوششیں کرو کبھی کامیاب نہیں ہو سکو گے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسلام ہمیشہ طاقتور رہے گا.جس طرح سورج ایک وقت مقررہ کے بعد ڈوب جاتا ہے اسی طرح اسلام پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جب اس میں تنزل کے آثار پیدا
Page 216
ہو جائیں گے.لیکن ابھی شفق کی سرخی اس میں باقی ہو گی.بے شک دن کی روشنی نہیں رہے گی مگر رات کی تاریکی بھی اس وقت نہیں ہو گی.ایک ملی جلی کیفیت ہو گی.مسلمانوں کا غلبہ بھی ہو گا اور ان میں ضعف اور اضمحلال بھی پیدا ہو چکا ہو گا.لیکن پھر اس کے بعد ہم رات کو شہادت کے طور پر پیش کرتے ہیں.اور ان سب چیزوں کو جنہیں رات اپنے اندر جمع کر لیتی ہے یعنی جو جو مصائب اور مشکلات رات کے اندر پائی جاتی ہیں وہ سب کی سب اس رات میں اکٹھی ہو جائیں گی اور وہ تمام تاریکیوں کو جمع کر کے ایک بھیانک صورت اختیار کر لے گی وَالْقَمَرِ اِذَااتَّسَقَ اس کے بعد ہم ایک چاند کو شہادت کے طور پر پیش کرتے ہیں جو تیرھویں رات کا ہو گا.یہ قرینہ صاف طور پر بتا رہا ہے کہ یہاں رات سے حقیقی رات مراد نہیں بلکہ استعارۃً رات کا ذکر کیا گیا ہے.کیونکہ ہر شخص جانتا ہے کہ تیرہویں یا چودھویں رات کے چاند انتہائی تاریک رات کے بعد نہیں نکلتے بلکہ تاریک راتوں کے شروع ہونے سے پہلے یہ چاند نکلا کرتے ہیں.پس اگر لیل سے مراد یہاں اصلی رات ہوتی تو وَالَّیْلِ وَمَاوَسَقَ کے بعد قمر کا کوئی ذکر ہی نہ ہوتا.کیونکہ مادی دنیا میں اس قسم کی تاریک رات کے بعد کبھی تیرہویں یا چودھویں کا چاند نہیں نکلا کرتا.یہ قرینہ بتا رہا ہے کہ اس جگہ ظاہری رات کا ذکر نہیں ہو رہا بلکہ ایسی رات کا ذکر کیا جا رہا ہے جس کے انتہائی طور پر تاریک ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے قمر ظاہر ہوا کرتا ہے.اِتِّسَاق کے معنے جیسا کہ اس سورۃ کی تفسیر میں بتایا جا چکا ہے تیرہویں، چودھویں، پندرہویں اور سولہویں رات کے چاند کے ہوتے ہیں.پس اس آیت میں یہ خبر دی گئی ہے کہ جس طرح دن غائب ہوتا ہے اسی طرح اسلام کا حال ہو گا.اس کا تنزل ایک دم نہ ہو گا بلکہ آہستہ آہستہ وہ تنزل کی طرف جائے گا.یہاں تک کہ اسلام کا سورج لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جائے گا مگر اس کی شفق باقی رہ جائے گی.اس کے بعد شفق بھی جاتی رہے گی اور کامل تاریکی مسلمانوں پر چھا جائے گی.اس کے بعد ایک چاند نکلے گا جو تیرہویں رات میں ظاہر ہو گا اور سولہویں رات تک جائے گا.اور وہ تیرہویں تاریخ کا چاند اسلام کے تمام مصائب کا خاتمہ کر دے گا.اور یہ ترقی کا سلسلہ سولہویں صدی تک چلتا چلا جائے گا خدا تعالیٰ نے اس حقیقت کے اظہار کے لئے اِتِّسَاق کا لفظ بھی عجیب رکھا ہے.لغت میں لکھا ہے اس کے معنے اس چاند کے ہیں جو تیرہویں، چودہویں، پندرہویں اور سولہویں تاریخ کا ہو اگر تیرہویں اور چودھویں رات کو ابتدا سمجھا جائے تو پندرہویں اور سولہویں رات اس چاند کے ظہور کی انتہائی راتیں سمجھی جائیں گی.بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے گو اسلام پر تنزل کا زمانہ آئے گا مگر تیرہویں صدی میں چاند کا ظہور ہو جائے گا اور یہ تکلیف دہ زمانہ دور ہو جائے گا.چنانچہ آگے فرماتا ہے لَتَرْکَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ تم طبق بہ طبق اور درجہ
Page 217
بدرجہ ان ساری حالتوں میں سے گذرو گے تم پر تاریکی کے دَور بھی آئیں گے اور روشنی کے بھی.غلبہ کے ایّام بھی آئیں گے اور تنزل کے بھی.ابتدا میں تمہاری حالت شفق کے مشابہ ہو گی اس کے بعد رات اپنی تمام تاریکیوں کو جمع کر کے بھیانک صورت اختیار کر لے گی.پھر اس کے بعد چاند نکلے گا جو تمام تاریکیوں کو پھاڑ دے گا اور اسلام کی مشکلات کا خاتمہ ہو جائے گا.اس سے صاف پتہ لگتا ہے کہ یہاں ظاہری راتیں مراد نہیں بلکہ باطنی راتیں مراد ہیں اور مسلمانوں کے تنزل اور پھر ان کی دوبارہ ترقی کا ان آیات میں نقشہ کھینچا گیا ہے.اسی طرح سورۂ بروج میں فرماتا ہے وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الْبُرُوْجِ(البروج:۲).یعنی ہم آسمان کو شہادت کے طور پر پیش کرتے ہیں جو بروج والا ہے.وَالْیَوْمِ الْمَوْعُوْدِ(البروج:۳) اور ہم شہادت کے طور پر یومِ موعود کو بھی پیش کرتے ہیں.علم ہیئت کے ماہرین بارہ ستاروں کے لئے بارہ بُرج قرار دیتے ہیں اس لحاظ سے ذَاتِ الْبُرُوْجِ سے مراد وہ آسمان ہو گا جو بارہ بُرجوں والا ہے اور آیت کے یہ معنے ہوں گے کہ ہم آسمان کو شہادت کے طور پر پیش کرتے ہیں جو بارہ بُرجوں والا ہے.اور پھر اس کے ساتھ ہی یومِ موعود کو بھی پیش کرتے ہیں یعنی تیرہویں زمانہ کو.تیرہویں صدی میں اسلام کے احیاء کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مقدس انسان مبعوث ہونے والا ہے جس کی تشریح اگلی آیت میں ہی ان الفاظ میں فرمائی کہ وَشَاھِدٍ وَّ مَشْھُوْدٍ(البروج:۴) وہ وجود گواہ بن کر آئے گا ایک اور وجود کے لئے جو مشہود ہو گا اور جس کی صداقت کی گواہی دی جائے گی.یعنی مسیح موعودؑمبعوث ہو گا تاکہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور قرآن مجید کی سچائی کا گواہ ہو.اور اسلام کا زوال رو بہ ترقی ہو.اس آیت سے بھی تیرہویںصدی میں ایک شاہد کے ظہور کا ثبوت ملتا ہے.اسی طرح احادیث میں آتا ہے.خَیْرُکُمْ قَرْنِیْ ثُمَّ الَّذِیْنَ یَلُوْنَـھُمْ..............ثُمَّ یَکُوْنُ بَعْدَ ھُمْ قَــــوْمٌ یَــــشْـــــھَــــدُوْنَ وَلَا یُــسْـــتَــشْــھَــدُوْنَ وَیَـــخُــوْنُــوْنَ وَلَا یُـــؤْتَـــمَــنُــوْنَ وَیَــنْــذُرُوْنَ وَلَایَفُـــوْنَ وَیَظْھَرُ فِیْـھِمْ السِّمَنُ.(صــحیح بـخاری کتاب الرقاق باب ما یـحذر من زھرۃ الدنیا والتّنافس فیـھا ) یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بہتر میری صدی ہے پھر بعد کی صدی اور پھر اس سے بعد کی صدی مگر اس کے بعد ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو گواہی دیں گے تو لوگ کہیں گے تمہاری گواہی کا کیا اعتبار تم تو جھوٹ بولنے کے عادی ہو.کوئی شخص ان کے پاس امانت رکھنے کے لئے تیار نہیں ہو گا.کیونکہ وہ سخت خائن اور بددیانت ہوں گے.اسی طرح ان کا حال یہ ہو گا کہ وہ نذریں مانیں گے تو ان کو پورا نہیں کریں گے اور کھا کھا کر خوب موٹے ہو جائیں گے.دین کی رغبت اور قربانی کا جذبہ ان کے دلوں میں نہیں رہے گا.
Page 218
ان سب آیات اور پیشگوئیوں کو ملانے سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے تین صدی تک اسلام کی ترقی کا زمانہ ہو گا اس کے بعد دس صدیوں کا لمبا زمانہ اس پر تنزل کا آئے گا.جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وقت مقررہ پورے کا پورا ہی شمار ہو جب تک کہ کوئی خاص قرینہ نہ ہو بلکہ ایک سال کا اکثر حصہ ایک سال اور دن کا ایک کثیر حصہ ایک دن اور صدی کا ایک کثیر حصہ ایک صدی کہلا سکتا ہے.پس حدیث کی مقرر کردہ تین صدیوں کو جن کے بعد فتنہ فساد پھیل جانا ہے قرآن کریم کے دو سو اکہتر۲۷۱ سالوں سے اختلاف نہیں.بلکہ ایک جگہ عرصہ زیادہ معین کر دیا گیا ہے اور دوسری جگہ عرفی الفاظ استعمال کر دیئے گئے ہیں.الغرض اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالْفَجْرِ.وَلَیَالٍ عَشْرٍ کہ ہم اس فجر کی اور ان دس راتوں کی قسم کھاتے ہیں جو اس فجر سے پہلے آئیں گی اور اس سے مراد وہ ہزار سالہ دَورِ تنزّل اور دَورِ ضُعف ہے جو اسلام پر پہلی تین صدیوں کے بعد آیا اور ہر رنگ میں تنزّل آنا شروع ہوا یہاں تک کہ ساری تاریکیاں جمع ہو گئیں گویا جس طرح پہلے دَور کے متعلق ایک رات ایک سال کی قائم مقام تھی دوسری پیشگوئی میں ایک رات ایک صدی کی قائم مقام ہے.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان تاریک راتوں کے بعد فجر کا زمانہ آئے گا اور تاریکی و ظلمت کے بادل آسمانِ روحانیت پر سے پھٹ جائیں گے.چنانچہ اسی مناسبت سے مسیح موعودؑ کا ایک نام طارق رکھا گیا ہے.حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کو بھی پہلا الہام وَالسَّمَآءِ وَالطَّارِقِ ہوا(تذکرہ صفحہ ۲۴).اور یہ الہام آپؑکو آپؑکے والد کی وفات کے وقت ہوا.حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس کے معنے ان کی وفات کے کئے ہیں کیونکہ ان کی وفات رات کو ہوئی.مگر اس کے معنے صبح کے ستارہ کے بھی ہوتے ہیں اور والد کی وفات کے وقت جب آپ کو فکر ہوئی کہ والد فوت ہو جائیں گے تو کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم تو طارق ہو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو ظاہر کرنے والے ہو.پس تمہارے والد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں.اس دنیوی والد کی وفات کا تم کو کیا غم ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ الٓمّٓرٰ کے ابجدی اعداد کو اگر فیج اعوج کے ہزار سال سے ملایا جائے اور پھر اس سارے حساب کو عیسوی بنانے کے لئے اس میں ۶۲۱ سال وہ شامل کئے جائیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے زمانہ تک سنہ عیسوی کے لحاظ سے بنتے ہیں تو عین وہ سنِ عیسوی نکل آتا ہے جس میں فجر کا طلوع ہوا اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے دنیا کے سامنے اپنا دعویٰ پیش فرمایا.الٓمّٓرٰ کے اعداد ۲۷۱ ہیں اس میں دس صدیاں شامل کی جائیں تو ۱۲۷۱ بن جاتا ہے پھر ۱۲۷۱ میں ۶۲۱ سال پہلے شامل کئے جائیں تو ۱۸۹۲ بن جاتے ہیں.اب اس میں دو یا تین سال ہمیں بہرحال نکالنے پڑیں گے کیونکہ الٓمّٓرٰ سورۂ رعد میں آتا ہے جو مکی سورۃ ہے اور ہجرت سے دو تین سال پہلے نازل ہوئی تھی.اب
Page 219
اگر دو سال نکال دیں تو ۱۸۹۰ رہ جاتے ہیں اور یہ وہی سال ہے جس میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے دعویٰ کیا.اور اگر تین سال نکال دیں تو ۱۸۸۹ رہ جاتے ہیں اور یہ وہ سال ہے جس میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے لوگوں سے بیعت لی.حضرت مسیح موعودؑ کے دعوے کی تاریخ کا بیان اسی طرح اگر ہم ہجری سنہ کا حساب کریں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمودہ تین صدیوں کو لَیَالٍ عَشْرٍ میں شامل کریں تو یہ ۱۳۰۰ بن جاتا ہے اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس کے بالکل قریب یعنی ۱۳۰۸ ہجری میں دعویٰ فرمایا ہے.اور سات یا آٹھ ایسا چھوٹا دہاکا ہے کہ تیرہ صدیوں کے ذکر میں ان کو شمار ہی نہ سمجھا جائے گا.پھر اگر ہم ایک اور لحاظ سے دیکھیں تو اس سے براہین احمدیہ کی پیشگوئی نکل آتی ہے.براہین احمدیہ ۱۳۰۰ھ میں لکھی گئی اور ۱۳۰۲ ہجری میں شائع ہوئی ہے اور یہ وہی سال ہے جس میں قرآنی پیشگوئی کے مطابق فجر کا طلوع مقدر تھا.گویا شمسی اور قمری دونوںلحاظ سے یہ پیشگوئی پوری ہوئی اور رات کی تاریکیوں کو دور کرنے کے لئے اُفقِ آسمان سے الطارق کا ظہور ہو گیا.یہ کتنی زبردست پیشگوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے طلوعِ فجر کی تاریخیں تک بتا دی گئیں اور سینکڑوں سال پہلے ان کا ذکر کر دیا گیا اور پھر اس کے مصداق کو عین انہی تاریخوں میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہدایت کے لئے کھڑا کیا جو قرآن اور احادیث میں اس کے ظہور کے لئے مقرر کی گئی تھیں.یہ خدا تعالیٰ کا ایسا عظیم الشان نشان ہے جس پر غور کرنے سے اس کی ہستی اور قدرت پر زندہ ایمان پیدا ہوتا ہے اور ہر شخص جو تعصّب سے خالی ہو اسے اقرار کرنا پڑتا ہے کہ اسلام خدا تعالیٰ کا سچا مذہب ہے.شفع اور وتر کا مطلب اسلام کے دوبارہ احیاء کے اعتبار سے اب رہا پیشگوئی کا تیسرا حصہ یعنی وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ اس کے دو۲ معنے ہو سکتے ہیں ایک تو یہ کہ شفع اور وَتر کا جو معاملہ ہو گا اسے ہم شہادت کے طور پر پیش کرتے ہیں.یاد رکھنا چاہیے کہ اس آیت میں بعد کے واؤ عطف کے ہیں اور مراد یہ ہے کہ ہم اس کی بھی قسم کھاتے ہیں اور اس کی بھی قسم کھاتے ہیں.لیکن وَالْفَجْرِ میں واؤ قسم کے لئے آیا ہے کیونکہ اس سے پہلے کوئی اور مضمون نہیں کہ ہم اس واؤ کو عاطفہ قرار دے سکیں.وَالْفَجْرِ دراصل اُقْسِمُ بِالْفَجْرِ ہے اور واؤ کو اُقْسِمُ کا قائم مقام بنایا گیا ہے لیکن اس کے بعد جتنے واؤ ہیں سب اَلْفَجْرِ کے بعد جو امور مذکور ہوئے ہیں انہیں معطوف بنانے کے لئے آئے ہیں.اس لحاظ سے وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ کے یہ معنے ہوں گے کہ ’’اور ہم شہادت کے طور پر پیش کرتے ہیں اس معاملہ کو جو شفع اور
Page 220
وَتر کا ہے‘‘ جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غارِ ثور میں گئے تھے اور حضرت ابو بکرؓ آپؐکے ساتھ تھے تو آپؐنے فرمایا تھا لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰہَ مَعَنَا غم مت کر خدا ہمارے ساتھ ہے اسی طرح جب شاہِد و مشہود جمع ہوجائیں گے یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ ظاہر ہوں گے اور آپؐکا ایک خادم بھی جو آپؐکا بروز ہو گا ظاہر ہو گا تو وہ وقت بھی اسلام کے لئے نہایت سخت ہو گا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شاگرد سمیت گویا محصور ہو جائیں گے تب وَتر یعنی اللہ تعالیٰ پھر اس بات کو ثابت کرے گا کہ وہ ان کے ساتھ ہے.چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کا الہام ہے:.’’رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ گزیں ہوئے قلعۂ ہند میں.‘‘ (تذکرہ صفحہ ۴۶۶) یعنی جس طرح پہلے کفار کے حملہ سے بچنے کے لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں پناہ لی اور حضرت ابوبکرؓ آپؐکے ساتھ تھے اسی طرح آخری زمانہ میں آپ کی روحانیت کفر سے بچنے کے لئے قلعۂ ہند پناہ گزیں ہوئی ہے.اس الہامِ الٰہی نے صاف بتا دیا کہ دوسری غارِ ثور ہندوستان میں ہونے والی ہے.پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم غارِ ثور میں پناہ لیں گے.پھر آپؐکے ساتھ آپؐکا ایک ساتھی ہوگا، اور پھر آپؐاسے فرمائیں گے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کی نصرت سے وہ قید ہی کامیابی کا ذریعہ ہو جائے گی.پس وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ میں یہ بتایا گیا ہے کہ جس طرح پہلے غار ثور میں حضرت ابوبکرؓ کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پناہ گزیں ہوئے تھے اس آخری دَور میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسیح موعودؑ کے ساتھ پناہ گزیں ہوں گے مگر اس دفعہ غارِ ثور میں نہیں بلکہ قلعۂ ہند میں پناہ گزیں ہوں گے اور پھر خدا تعالیٰ ان کی معیّت کے لئے اپنے فرشتوں کی فوج کے ساتھ اترے گا جس طرح کہ غار ثور کے وقت اترا تھا.علاوہ ازیں وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ کے ایک اور معنے بھی ہو سکتے ہیں اور وہ یہ کہ درمیانی عطف کو اَلْفَجْرِ کی طرف منسوب نہ کیا جائے بلکہ شفع کی طرف پھیرا جائے اس صورت میں اس کے یہ معنے نہ ہوں گے کہ ہم قسم کھاتے ہیں شفع کی اور ہم قسم کھاتے ہیں وَتر کی بلکہ اس کے معنے یہ لئے جائیں گے کہ ہم قسم کھاتے ہیں شفع کی اور اس کے ساتھ تعلق رکھنے والے وَتر کی.گویا وَتر کی علیحدہ قسم نہیں کھائی بلکہ شفع اور وتر کو ملا کر ان کی قسم کھائی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ ایسے وجود کو ہم بطور شاہد پیش کرتے ہیں جو اپنی ذات میں شفع بھی ہے اور وتر بھی ہے.اس صورت میں اس آیت کے یہ معنے ہوں گے کہ میں اس شفع کو شہادت کے طور پر پیش کرتا ہوں جو ساتھ ہی وَتر بھی ہے.یعنی
Page 221
ایک جہت سے وہ شفع ہے اور ایک جہت سے وَتر ہے.اور یہ مطلب ہو گا کہ لَیَالٍ عَشْرٍ کے بعد جو فجر ظاہر ہو گی وہ ایسے وجود کے ذریعہ سے ظاہر ہوگی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غیر ہوتے ہوئے پھر غیر کہلانے کا مستحق نہیں ہو گا.بظاہر وہ دوسرا ہو گا اور شفع کہلائے گا لیکن باوجود ایک دوسرا شخص ہونے کے اس کے آنے سے دو نبی نہیں ہو جائیں گے دو امام نہیں ہو جائیں گے بلکہ وہ ایسا فنا فی الرّسول ہو گا کہ باوجود اس کے آنے کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کے ایک ہی رہیں گے.یعنی وہ یہ کہے گا ع وہ ہے میں چیز کیا ہوں بس فیصلہ یہی ہے (قادیان کے آریہ اور ہم روحانی خزائی جلد ۲۰ صفحہ ۴۵۶) اور وہ کہے گا کہ مَنْ فَرَّقَ بَیْنِیْ وَبَیْنَ الْمُصْطَفٰی فَـمَا عَرَفَنِیْ وَمَا رَاٰی (خطبہ الہامیہ روحانی خزائن جلد ۱۶ صفحہ ۲۵۹).جس نے کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدہ وجود ہوں.وہ الگ ہیں اور میں الگ فَـمَا عَرَفَنِیْ وَمَا رَاٰی اس نے مجھے نہیں پہچانا بلکہ وہ تو گمراہ ہو گیا.مجھے ایک دفعہ یہی مضمون خواب میں دکھایا گیا تھا.مقبرہ بہشتی کی طرف جاتے ہوئے مدرسہ احمدیہ اور بکڈپو کے درمیان سے جو گلی گذرتی ہے.اور جس کے آگے کنواں آ جاتا ہے یہاں پہلے ایک چھوٹا سا میدان تھا.اب تو وہاں کمرے بن چکے ہیں.میں نے رؤیا میں دیکھا کہ اس میدان میں ایک کرسی بچھائی گئی ہے اور کسی نے کہا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم تشریف لا رہے ہیں.اتنے میں میں نے دیکھا کہ ایک طرف سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں.جب دوسری طرف میں نے نگاہ اٹھائی تو میں نے دیکھا اس طرف سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام تشریف لا رہے ہیں اور دونوں کے منہ اس کرسی کی طرف ہیں.خواب میں میں سخت گھبراتا ہوں کہ یہ کیسی خطرناک غلطی ہوئی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم بھی تشریف لا رہے ہیں اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام بھی تشریف لا رہے ہیں لیکن کرسی ایک ہے یہ تو بڑی ہتک آمیز بات ہے مگر اس وقت نہ مجھ سے اٹھا جاتا ہے کہ میں دوڑ کر کوئی اور کرسی لے آؤں اور نہ کسی اور کو یہ خیال آیا.اس وقت میرا دل خوف سے دھڑک رہا ہے اور جوں جوں وہ قریب آ رہے ہیں میرا اضطراب بڑھتا چلا جاتا ہے.یہاں تک کہ وہ دونوں کرسی کے قریب پہنچ گئے.اس وقت مجھے خیال آیا کہ اب شاید حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام پیچھے ہٹ جائیں گے مگر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام پیچھے نہ ہٹے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آگے کی طرف بڑھے.اس وقت مجھے ایسا معلوم ہوا کہ میرے دل کی حرکت بند ہوجائے گی مگر تھوڑی دیر کے بعد ہی میں نے دیکھا کہ دونوں نے اپنے اپنے جسم کو ذرا سا ٹیڑھا کر
Page 222
کے کرسی پر بیٹھنے کی کوشش کی.اور اس کے بعد ان کے دھڑ ایک دوسرے میں داخل ہونے شروع ہو گئے.اور جب وہ کرسی پر بیٹھ گئے تو دو نہیں بلکہ ایک ہی وجود نظر آنے لگا.یہی حقیقت اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمائی ہے کہ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ہم تمہارے سامنے اس شفع کو شہادت کے طور پر پیش کرتے ہیں جو شفع کے ساتھ وَتر بھی ہو گا.بظاہر وہ دو۲ ہوں گے لیکن درحقیقت وہ دو۲ نہیں بلکہ ایک ہی وجود ہو گا.دوسرے اس کے یہ معنے ہوں گے کہ ایسا وجود ظاہر ہو گا جسے لوگ دو۲ سمجھتے ہوں گے یعنی مہدی اور عیسٰی.لیکن وہ وتر ہو گا یعنی ایک ہی وجود کے یہ دونوں نام ہوں گے.اور باوجود شفع سمجھے جانے کے جب وہ ظاہر ہو گا تو وَتر ثابت ہو گا.میں سمجھتا ہوں اس قسم کی مثال پہلے کسی زمانہ میں نہیں ملتی کہ لوگ دو مدعیوں کے امیدوار ہوں لیکن جب وقت آئے تو وہ دو۲ موعود ایک ہی موعود ثابت ہوں.صرف یہی ایک زمانہ ہے جس میں لوگ کہتے تھے کہ ایک مسیحؑ ہو گا اور ایک مہدیؑ ہو گا.مگر جب وہ آیا تو وتر تھا یعنی پیشگوئیوں کے لحاظ سے دو۲ کی خبر دی گئی تھی مگر حقیقت کے لحاظ سے وہ دو۲ نہیں تھے بلکہ ایک ہی وجود کے دو۲ مختلف نام تھے.یہی بات اس آیت میں بیان کی گئی تھی کہ یہ دونوں نام ایک ہی وجود کے ہوں گے.اور باوجود شفع سمجھے جانے کے جب وہ ظاہر ہو گا تو وتر معلوم ہوگا.غرض اس صورت میں وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ میں یہ بتایا گیا ہے کہ آنے والے کی دو حقیقتیں ہوں گی.ایک حقیقتِ شفع اور ایک حقیقتِ وتر.وہ ایک علیحدہ وجود ہو گا اس لئے بظاہر اسلام میں دو۲ نبی نظر آئیں گے مگر چونکہ وہ فنا فی الرسول ہو کر یہ درجہ پائے گا اور اسلام پر ہی عمل کرے گااور اسی پر عمل کرائے گا.اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھے گا اور وہی لوگوں سے پڑھوائے گا اس لئے دوئی کوئی پیدا نہ ہو گی بلکہ اسلام میں ایک ہی نبی رہے گا دو۲ نہ ہوں گے.کیونکہ دو۲ تو اختلاف سے ہوتے ہیں.اتحاد سے دو ایک ہو جاتے ہیں.اور دوسرے یہ کہ دو۲ کاموں کی وجہ سے اسے دو۲ عہدے ملیں گے مگر درحقیقت وہ ایک ہی وجود ہو گا.اسلام کے دوبارہ غلبہ کے سالوں کا ذکر پھر فرماتا ہے وَالَّیْلِ اِذَا یَسْرِ.اس حصہ آیت میں پھر ایک اور صدی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو دس تاریک راتوں کے بعد کی ہے.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے معاً بعد اسلام کی ترقی نہ ہو گی وہ فجر تو اُ ن کے بعد ظاہر ہو جائے گی، شعاعِ نور نظر آ جائے گی اور لوگوں کی امیدیں بندھ جائیں گی مگر ابھی رات نہ جائے گی بلکہ ایک صدی کا ابھی وقفہ ہو گا.اب اگر ۱۸۹۰ء کو فجر لے لو تو یہ صدی
Page 223
۱۹۹۰ء تک چلتی ہے.آج کل ۱۹۴۵ء ہے اس لحاظ سے چھیالیس ۴۶ سال ابھی اس لیل میںباقی رہتے ہیں.اور اگر ہجری سال لے لو اور ۱۲۷۱ کو دس تاریک راتوں کا آخری سال قرار دے دو تو یہ صدی ۱۳۷۱ میں ختم ہوتی ہے.گویا اس لحاظ سے لیل کے ختم ہونے میں صرف ۸ سال باقی رہتے ہیں.اور اگر صدی کا سر مراد لو اور ۱۴۰۰ہجری میں اس لیل کا اختتام سمجھو تو اس میں ۳۷ سال باقی رہتے ہیں.یہ تین مدتیں ہیں جو تین مختلف جہتوں سے پیدا ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان میں سے کون سی جہت حقیقی ہے اور کون سی غیر حقیقی.یہ بھی ممکن ہے کہ تینوں جہتیں ہی حقیقی ہوں جیسے دس راتوں کی پیشگوئی کے بارہ میں مَیں نے بتایا تھا کہ آپؑکے دعویٰ کے لحاظ سے ایک رنگ میں پیشگوئی پوری ہو جاتی ہے.بیعت کے لحاظ سے دوسرے رنگ میں اور براہین احمدیہ کی اشاعت کے لحاظ سے تیسرے رنگ میں.اسی طرح ممکن ہے کہ جانے والی ایک رات کا ایک ظہور آٹھ سال بعد ہو یعنی ۱۹۵۲ء میں ایک ظہور ۳۷سال بعد ہو یعنی ۱۹۸۱ء میں.ایک ظہور چھیالیس سال بعد ہو یعنی ۱۹۹۰ء میں.قمری لحاظ سے چونکہ ایک صدی میں تین سال کی کمی آ جاتی ہے اس لئے ۳۷ سالہ معیاد میں سے اگر تین سال نکال دیئے جائیں تو ۳۴ سال رہ جاتے ہیں.اس لحاظ سے یہ لیل ۱۳۹۷ ہجری میں ختم ہو گی.گویا تین کی بجائے چار جہتیں ہو گئیں.چونکہ ابھی یہ پیشگوئی پوری نہیں ہو ئی اس لئے جتنے نقطۂ ہائے نگاہ سے بھی تعیین کی جا سکے ہمیں ان سب کو مدنظر رکھنا چاہیے.ایک نقطۂ نگاہ سے اس لیل کے جانے میں صرف آٹھ سال باقی رہتے ہیں.ایک نقطۂ نگاہ سے ۳۴سال باقی رہتے ہیں.ایک نقطۂ نگاہ سے ۳۷ سال باقی رہتے ہیں اور ایک نقطۂ نگاہ سے ۴۶ سال باقی رہتے ہیں.اس عرصہ میں یقیناً دوبارہ اللہ تعالیٰ کے کسی جلوہ کے ساتھ یوم الفرقان ظاہر ہوگا اور کسی خاص نشان کے ذریعہ احمدیت کو تقویت حاصل ہو گی.گو جیسا کہ بدر کی جنگ آخری جنگ نہیں تھی اس کے بعد بھی لڑائیاں ہوتی رہیں.اسی طرح اس کے بعد بھی مخالفین سے ہماری لڑائیاں جاری رہیں گی.مگر بہرحال احمدیت کو اس وقت تک ایسے رنگ میں غلبہ میسر آ جائے گا کہ دشمن اس کو محسوس کرنے لگ جائے گا.اسلام اور احمدیت کی کامل فتح تو جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے تحریر فرمایا ہے قریباً تین سو سال کے عرصہ میں ہو گی.اس کے بعد جو قومیں احمدیت میں شامل نہیں ہوں گی ان کی حیثیت بالکل ایسی ہی رہ جائے گی جیسے آج کل یہود کی ہے.بہرحال وہ آخری ترقی خواہ کچھ لمبے عرصہ کے بعد ہو احمدیت کی ایک فتح یا آج سے آٹھ سال بعد ہو گی یا آج سے ۳۴ سال بعد ہو گی یا آج سے ۳۷ سال بعد ہو گی یا آ ج سے ۴۶ سال بعد ہوگی.یا ان سالوں کے لگ بھگ وہ فتح ظاہر
Page 224
ہوجائے گی کیونکہ پیشگوئیوں میں دن نہیں گنے جاتے بلکہ ایک موٹا اندازہ بتایا جاتا ہے.اور جیسا کہ میں نے بتایا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان چاروں اوقات میں چار مختلف قسم کی فتوحات ظاہر ہوں.پس ان سب سالوں میں یا ان سالوں کے لگ بھگ ضرور کسی نہ کسی رنگ میں احمدیت کو فتح حاصل ہو جائے گی.فتح و نصرت کے نشانات قریب قریب عرصہ میں ظاہر ہونے سے یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ مومنوں کے ایمان ساتھ کے ساتھ تازہ ہوتے رہتے ہیں.جیسے گھر سے بخیریت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلامتی کے ساتھ نکل آئے تو مومنوں کو ایک خوشی پہنچی.جب غارِ ثور میں دشمنوں کے حملہ سے بچ گئے تو دوسری خوشی پہنچی.مدینہ پہنچے تو تیسری خوشی حاصل ہوئی.بدر کی جنگ میں کفار کو شکست ہوئی تو چوتھی خوشی پہنچی.اسی طرح ممکن ہے اللہ تعالیٰ ان چاروں مدتوں میں سے ہر مدت کے اختتام پر فجر کی ایک لَو ظاہر کرتا رہے.اور اس طرح مومنوں کے ایمانوں کو تقویت دیتا رہے.اسی رات کی نسبت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے اشعار میں فرمایا ہے ؎ دن چڑھا ہے دشمنانِ دیں کا ہم پر رات ہے اے مرے سورج نکل باہر کہ میں ہوں بے قرار (براہین احمدیہ جلد پنجم روحانی خزائن جلد ۲۱ صفحہ ۱۲۹) هَلْ فِيْ ذٰلِكَ قَسَمٌ لِّذِيْ حِجْرٍؕ۰۰۶ کیا اس میں عقل مند کے لئے کوئی قسم ہے؟ (یانہیں).حلّ لُغات.حِـجْرٌ.حِـجْرٌ کے معنے عقل کے ہیں (اقرب) اور ذِیْ حِـجْرٍ کے معنے ہوئے عقل مند انسان.تفسیر.هَلْ فِيْ ذٰلِكَ قَسَمٌ لِّذِيْ حِجْرٍ کے لفظی معنے تو یہ ہیں کہ کیا اس میں قسم ہے عقل مند انسان کے لئے.یا کیا اس میں شہادت ہے عقل مند انسان کے لئے.مگر هَلْ سے یہ مراد نہیں کہ قسم ہے یا نہیں بلکہ هَلْ کا سوال لفظ عربی زبان میں تصدیق کے لئے آتا ہے( مغنی اللبیب زیر لفظ ’’ھل‘‘) جیسے اردو میں کہتے ہیں کہ کیوں ایسا ہو گیا یا نہیں، اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا ضرور ہو گیا ہے.پس چونکہ اس جگہ هَلْ کے لفظ سے سوال کیا گیا ہے اس کے یہ معنے نہیں کہ لوگو بتاؤ کے اس میں عقل مند کے لئے قسم ہے یا نہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ کیا تم اس سے انکار کر سکتے ہو کہ اس میں عقل مند کے لئے قسم ہے.اور ہر عقل مند انسان کو اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا ہونے کی
Page 225
شہادت اس دلیل میں مل جانی چاہیے.لِذِیْ حِجْرٍ کے الفاظ کا استعمال صاف بتا رہا ہے کہ گذشتہ عظیم الشان نشانات کو پیش کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ اب تو عقل مند انسان کی سمجھ میں یہ آ جانا چاہیے کہ جو کچھ دعویٰ کیا جا رہا ہے اس کے دلائل بیّنہ اور براہینِ قاطعہ موجود ہیں اور جب یہ ظاہر ہوں گے اس وقت تمہیں ماننا پڑے گا کہ واقعہ میں خدا تعالیٰ نے عظیم الشان غیب کی خبریں دی ہیں.یہ کہہ دینا کہ مرزا صاحبؑنے یوں ہی ایک دعویٰ کر دیا ہے اور بات ہے مگر سوال یہ ہے کہ ایسے شخص کے دل میں یہ خیال کس طرح پیدا ہو گیا کہ وہ ۱۸۹۰ء میں ہی دعویٰ کرے یا آپؑسے پہلے کسی کے دل میں یہ خیال کیوں پیدا نہ ہوا کہ وہ ۱۸۹۰ء میں یہ دعویٰ کر دے.یہ تعدا د اور سال بہرحال ایک حد تک مخفی تھے.پھر پہلے لوگوں کے دلوں میں ان کا خیال کیوں پیدا نہ ہوا اور کیوں آپؑنے ہی اس وقت دعویٰ کیا جس وقت پیشگوئیوں کے مطابق مدعی کا کھڑا ہونا ضروری تھا.پھر سوال یہ ہے کہ باقی لوگ کیوں کامیاب نہیں ہوئے اور آپ کیوں کامیاب ہو گئے.مہدی کا دعویٰ حضرت مرزا صاحبؑ سے پہلے اور بھی سینکڑوں لوگ کر چکے تھے پھر وجہ کیا ہے کہ وہ تو مٹ گئے اور جس نے ۱۸۹۰ء میں دعویٰ کیا اسے خدا نے طاقت عطا فرمائی.کیا یہ اس بات کا ثبوت نہیں کہ اس کا دعویٰ خدا تعالیٰ کی طرف سے تھا اتفاقی نہیں تھا.اگر اتفاقی ہوتا اور آپؑکی کامیابی ظاہری جدوجہد کا نتیجہ ہوتی تو بعض مدعیٔ مہدویت ایسے بھی ہوئے ہیں جنہوں نے ملک فتح کئے اور حکومت قائم کی اور گو وہ بعد میں تباہ ہوگئے مگر بہرحال ان کے لئے ترقی پانے کے زیادہ مواقع تھے لیکن اس کے باوجود ایک عارضی کامیابی کے بعد انہوں نے شکست کھائی اور ان کا نام ہمیشہ کے لئے مٹ گیا.اس کے مقابلہ میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کو کامیابی حاصل کرنے کے کوئی مواقع میسر نہیں تھے لیکن اس کے باوجود آپؑنے دنیا پر فتح پائی.پھر ایک اور فرق یہ ہے کہ آپؑنے انہی تاریخوں پر دعویٰ کیا جن تاریخوںکی قرآن کریم اور احادیث میں خبر دی گئی تھی مگر باقی لوگوں میں سے کسی نے آگے دعویٰ کر دیا اور کسی نے پیچھے.گویا وہ سب کے سب ’’مِس فائر‘‘ کر گئے اور صرف آپؑہی ایسے ثابت ہوئے جنہوں نے ٹھیک وقت پر لوگوں کے سامنے اپنا دعویٰ پیش کیا.باب نے دعویٰ کیا مگر اس نے بہت پہلے دعویٰ کر دیا.اس کے بعد بہاء اللہ نے دعویٰ کیا مگر اس کا دعویٰ بھی پہلے ہوا اور گو اس نے کچھ زمانہ ایسا پایا جس سے یہ امر مشتبہ ہو سکتا تھا.مگر عین اس سے پہلے جب کہ مہدی کی مخصوص علامت چاند اور سورج گرہن نے ظاہر ہونا تھا وہ اس دنیا سے چل بسا.گویا سب مدعی شہادت کے مواقع سے یا پہلے گذر گئے یا بعد میں پیدا ہوئے لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ایسے وقت میں دعویٰ فرمایا جب قرآن اور احادیث
Page 226
کی تمام پیشگوئیاں تقاضا کر رہی تھیں کہ کوئی مدعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھڑا ہو اور وہ لوگوں کی اصلاح کا فرض سرانجام دے.لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ حضرت مرزا صاحبؑ کو کون سی ترقی ایسی حاصل ہوئی ہے جس کی بنا پر ہم یہ یقین کر لیں کہ آپؑ اپنے دعویٰ میں سچے تھے.اس کا جواب یہ ہے کہ اوّل کوئی موعود ایسا نہیں گذرا جس کی ہرملک میں جماعت ہو.ہماری جماعت ایسے ایسے ممالک میں قائم ہے جہاں آج سے چند سال پہلے ایک احمدی بھی نہیں تھا.اور جہاں اسلام کا نام بھی نہیں پہنچا تھا.پھر بڑی بات یہ ہے کہ احمدیوں کو وہاں وہاں کام کرنے کا موقع ملا ہے جہاں دوسرے مدعیوں کا ایک فرد بھی نہیں پہنچا.مثلاً مغربی افریقہ ہے اس ملک کے رہنے والے لوگ ننگے پھرتے تھے.علم سے بے بہرہ تھے اور تہذیب وتمدن سے قطعی طور پر نا آشنا تھے.جب احمدی مبلغین وہاں تبلیغ کے لئے گئے تو ان کی وجہ سے ہزارہا لوگ انسانیت کے دائرہ میں شامل ہوئے اور انہوں نے بھی متمدن زندگی بسر کرنی شروع کر دی.درحقیقت اس قسم کے عملی کاموں سے ہی کسی قوم کی زندگی کا پتہ لگ سکتا ہے ورنہ خالی ٹریکٹ شائع کر دینے سے کچھ نہیں بنتا.ہماری جماعت کو خدا تعالیٰ کے فضل سے اس قسم کا کام کرنے کی توفیق ملی ہے جس قسم کا کام کرنے کی دوسرے مدعیوں کی جماعتیں قطعاً کوئی مثال پیش نہیں کر سکتیں.ترقی کی ایک اور علامت جو قرآن کریم سے ثابت ہوتی ہے اور جو خدا تعالیٰ کے فضل سے ہم میں تو پائی جاتی ہے لیکن دوسرے مدعیوں کی جماعتیں اس سے محروم ہیں وہ قوم کا ایک مرکز پر مجتمع ہونا ہے تاکہ اس کا شیرازہ منتشر نہ ہو اور وہ متحدہ طاقت سے دنیا میں تبلیغ کرنے کا پروگرام جاری رکھ سکے.مثلاً بہائیوں کا اس وقت تک کوئی مرکز نہیں لیکن جماعت احمدیہ کا قادیان مرکز ہے جہاں ہر سال ہزاروں لوگ آتے اور علمی اور روحانی لحاظ سے فائدہ اٹھا کر اپنے گھروں کو واپس جاتے ہیں.یہ وہ مرکز ہے جس کی نسبت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کو الہام ہوا کہ یَاْتِیْکَ مِنْ کُلِّ فَـجٍّ عَـمِیْقٍ.یَاْتُوْنَ مِنْ کُلِّ فَـجٍّ عَـمِیْقٍ (تذکرہ صفحہ ۴۸،۴۹) تیری طرف دور دور سے اور اس کثرت سے لوگ آئیں گے کہ سڑکوںمیں گڑھے پڑ جائیں گے.پھر آپؑ نے رؤیا میں قادیان کی ترقی کو دیکھا اور فرمایا.’’ہم نے کشف میں دیکھا کہ قادیان ایک بڑا عظیم الشان شہر بن گیا ہے اور انتہائی نظر سے بھی پرے تک بازار نکل گئے.اونچی اونچی دو منزلی یا چو منزلی یا اس سے بھی زیادہ اونچے اونچے چبوتروں والی دوکانیں عمدہ عمارت کی بنی ہوئی ہیں اور موٹے موٹے سیٹھ بڑے بڑے پیٹ والے جن سے بازار کو رونق ہوتی ہے بیٹھے ہیں اور ان کے آگے جواہرات اور لعل اور موتیوں اور ہیروں، روپوں اور اشرفیوں
Page 227
کے ڈھیر لگ رہے ہیں اور قسما قسم کی دوکانیں خوبصورت اسباب سے جگمگا رہی ہیں.یکّے ، بگھیاں، ٹم ٹم، فِٹن، پالکیاں، گھوڑے، شکرمیں، پیدل اس قدر بازار آتے جاتے ہیں کہ مونڈھے سے مونڈھا بھڑکر چلتا ہے اور راستہ بمشکل ملتا ہے.‘‘ (تذکرہ صفحہ ۳۹۳،۳۹۴) یہ پیشگوئی ہے جو قادیان کی ترقی کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمائی.اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپؑکو یہ خبر دی کہ لوگ اپنے وطنوں کو چھوڑ کر قادیان میں ہجرت کر کے آ جائیں گے (تذکرہ صفحہ ۵۱) چنانچہ ان پیشگوئیوں کے مطابق قادیان خدا تعالیٰ کے فضل سے روز بروز بڑھ رہا ہے اور ہزارہا لوگ قادیان میں ہجرت کر کے آ چکے ہیں.اپنے وطن کو چھوڑ دینا اور مال و املاک کو ترک کر کے ایک دوسرے شہر میں محض خدا کی رضا کے لئے ہجرت کر کے چلے جانا بڑی بھاری قربانی کی علامت ہوتی ہے اور جس قوم میں یہ قربانی پائی جاتی ہو وہ کبھی مٹ نہیں سکتی.اس کے مقابلہ میں عکّہ اور بہجہ میں جا کر دیکھ لو بہائی لوگ بیٹھے مکھیاں مارتے رہتے ہیں اور کوئی شخص بیرون جات سے ان کے پاس نہیں آتا.ہمارے آدمی سفر یورپ کے موقع پر وہاں گئے تو بہائی لوگ ان کے پیچھے پڑگئے کہ بہاء اللہ کی قبر کے انگور لے جاؤ.یہ بڑی برکت والے ہیں.گویا ان کی حالت بالکل مجاوروں کی سی ہے اور وہی مشرکانہ رسوم وہاں پائی جاتی ہیں جو ہندوستان میں بعض قبروں پر پائی جاتی ہیں.پھر وہاں ان کی ترقی کی جو حالت ہے اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب ہم عکّہ گئے تو جس سے بھی پوچھیں کہ بہائیوں کا مرکز کہاں ہے تو وہ کہتے کہ ہمیں تو علم نہیں.اس پر ہمیں بڑی حیرت ہوئی کہ ہم عکّہ میں بھی پہنچ گئے ہیں اور بہائیوں کے مرکز کا بھی ہمیں پتہ نہیں لگتا.آخر بڑی دیر کے بعد ایک شخص نے بتایا کہ آپ غلط سوال کر رہے ہیں بہائی اس علاقہ میں بہائیت کے نام سے نہیں بلکہ عجمیت کے نام سے مشہور ہیں اور ان کو سب لوگ یہاں عجمی کہتے ہیں.آپ عجمی کہہ کر دریافت کرتے تو کسی کو علم بھی ہوتا کہ آپ کن لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں.پھر اس نے بتایا کہ یہ عجمی بھی عکّہ میں نہیں رہتے بلکہ تین چار میل پرے ایک جگہ بہجہ ہے وہ وہاں رہتے ہیں.چنانچہ ہم موٹر لے کر وہاں پہنچے اور بہائیوں کے حالات کا مشاہدہ کیا.اس وقت ہمیں معلوم ہوا کہ چونکہ بعض پیشگوئیوں میں عکّہ کا لفظ آتا تھا اس لئے انہوں نے عکّہ کو اپنا مرکز لکھنا شروع کر دیا حالانکہ وہ عکّہ میں نہیں بلکہ اس سے بھی چار پانچ میل دور رہتے تھے اور پھر باوجود اس کے کہ سالہاسال سے باب اور بہاء اللہ کا دعویٰ تھا پھر بھی ان کی حالت یہ تھی کہ چار پانچ میل تک بھی لو گ ان کو نہیں جانتے تھے اور یہاں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی برکت سے یہ حالت ہے کہ کوئی شخص آپؑکا نام لے دے فوراً لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ مرزا صاحبؑکے ماننے والوں میں سے ہے بلکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃوالسلام
Page 228
کے نام پر احمدی بھی مرزائی کہلانے لگ گئے ہیں اور یا پھر لوگ ہماری جماعت کے دوستوں کو مولوی کہتے ہیں جس کے معنے ہیں علم والے مگر عجمی کا لفظ عرب میں ہمیشہ تحقیر کے لئے استعمال کیا جاتا ہے.اور عربی زبان میں اس کے معنے ہوتے ہیں اَن پڑھ اور جاہل لوگ.پس انہیں تو اپنے علاقہ میں اَن پڑھ اور جاہل کہا جاتا ہے اور یہاں احمدیوں کو مولوی کہا جاتا ہے جس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ علم والے ہیں.اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ترقی کا صحیح مقام ابھی ہماری جماعت کو حاصل نہیں ہوا اور ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے ساری دنیا فتح کر لی ہے مگر ’’ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات‘‘ ہمارا ایک مرکز ہونا، ہماری جماعت کا دنیا کے مختلف ممالک میں پھیل جانا، ہزاروں آدمیوں کا اپنے وطنوں کو چھوڑ کر قادیان میں ہجرت کر کے آ جانا اور ہمارا اپنی تعداد اور اپنے علم میں روز بروز بڑھتے جانا یہ اس بات کی علامات ہیں کہ ہم ایک دن ساری دنیا کو انشاء اللہ فتح کر لیں گے.اس وقت اگر قادیان کے محلوں اور اس کی پرانی اور نئی آبادی کا جائزہ لیا جائے تو سوائے ہمارے کہ ہم قادیان کے اصل باشندے ہیں اور سوائے محلّہ ارائیاں میں رہنے والے چند لوگوں کے کہ جن کی مجموعی تعداد کسی صورت میں بھی دو تین سو سے زیادہ نہیں ہو گی باقی سب کے سب وہ لوگ ہیں جو باہر سے ہجرت کر کے قادیان آئے.میں سمجھتا ہوں سو احمدیوں میںسے صرف ڈیڑھ فیصدی قادیان کے اصل باشندے ہیں باقی سب کے سب وہ لوگ ہیں جو باہر سے آئے ہیں.پھر ان باہر سے آنے والوں میں کوئی افغانستان سے آیا ہے کوئی برما سے آیا ہے کوئی مالابار سے آیا ہے کوئی سیلون سے آیا ہے کوئی سندھ سے آیا ہے کوئی بنگال سے آیا ہے.اسی طرح اور بیسیوں علاقے ہیں جہاں کے رہنے والے قادیان میں پائے جاتے ہیں.میں سمجھتا ہوں اگر یہ دیکھا جائے کہ قادیان میں کہاں کہاں سے لوگ آئے ہوئے ہیں تو اتنے مختلف مقامات سے آئے ہوئے لوگ ثابت ہوں گے کہ لاہور میں بھی اتنے مختلف مقامات کے لوگ موجود نہیں ہوں گے.یہ کوئی معمولی بات نہیں بلکہ بہت بڑی بات ہے اور اس الہام کی صداقت کا ایک زبردست ثبوت ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ہوا کہ یَاْتِیْکَ مِنْ کُلِّ فَـجٍّ عَـمِیْقٍ.یَاْتُوْنَ مِنْ کُلِّ فَـجٍّ عَـمِیْقٍ (تذکرہصفحہ ۴۸،۴۹) لوگ تیرے پاس دور دراز سے آئیں گے.پھر خدا تعالیٰ نے جماعت احمدیہ کو شاخ درشاخ اس طرح پھیلا دیا ہے کہ ہر قسم کے کارکن ہماری جماعت میں پائے جاتے ہیں.اگر ایک طرف زمیندار طبقہ ہماری جماعت میں پایا جاتا ہے تو دوسری طرف تاجروں کا بھی ایک کثیر حصہ ہماری جماعت میں موجود ہے.اسی طرح اگر عربی دان ہماری جماعت میں کثرت سے پائے جاتے ہیں تو انگریزی دان لوگوں کی بھی ہماری جماعت میں کمی نہیں ہے.غرض ہر طبقہ اور ہر شعبہ میں ہماری جماعت پھیل رہی ہے.اور ہر قسم کے کارکن ہماری جماعت کو میسر آ رہے ہیں مگر بہائیوں کو یہ بات نصیب نہیں.
Page 229
ان میں چند خاص قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں ہر طبقہ سے تعلق رکھنے والے لوگ ان میں نہیں پائے جاتے جو اس بات کی علامت ہے کہ ان کی جماعت کو وہ وسعت حاصل نہیں جو دنیا پر چھا جانے والی جماعتوں کو حاصل ہوا کرتی ہے.چند علمی رنگ میں بحثیں کرنے والے آدمیوں کا پیدا ہو جانا کسی جماعت کی زندگی کے لئے کافی نہیں ہوتا بلکہ یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ قربانی اور ایثار کا مادہ ان میں زیادہ سے زیادہ پایا جاتا ہو.وہ مرکز سے وابستگی رکھتے ہوں.اپنی تعلیم کی اشاعت کے لئے ہر مشکل کو برداشت کرنے والے ہوں اور یہ جذبہ اپنے دلوںمیں رکھتے ہوں کہ ہم مر جائیں گے مگر اس تعلیم کو نہیںچھوڑیں گے جس کو لے کر ہم کھڑے ہوئے ہیں.یہ جذبۂ قربانی اور ایثار و استقلال کا یہ مادہ ہماری جماعت میں تو پایا جاتا ہے مگربہائیوں میں اس قسم کی کوئی مثال نظر نہیں آتی.پھر جس قسم کی اشاعت کی توفیق ہماری جماعت کے مبلغوں کو ملی ہے ان کو نہیں ملی.ہماری جماعت کے مبلغ سارے جہان میں پھرتے اور لوگوں کو اسلام اور احمدیت میں داخل کرتے ہیں مگر ان کے اندر کوئی باقاعدہ تبلیغی نظام نہیں، نہ ان کے مبلغ غیر ممالک میں جاتے ہیں اور نہ تبلیغی جذبہ ان کے اندر پایا جاتا ہے.اسی طرح جس قسم کا کام ہماری جماعت کر رہی ہے اس قسم کے کام کی کوئی مثال بہائی اپنی جماعت کی طرف سے پیش نہیں کر سکتے.ہماری جماعت نے پسماندہ اقوام کو ابھارنے اور ادنیٰ اقوام کو اونچا کرنے اور ان میں تعلیم کو رائج کرنے اور انہیں مہذب اور متمدن بنانے کے لئے جس قدر کوششیں کی ہیں ان کا عشر عشیر بھی بہائیوں میں نہیں پایا جاتا.پھر تعداد کے لحاظ سے دیکھو تو ان کی ہمارے مقابلہ میں کوئی نسبت ہی نہیں.باوجود اس کے کہ انہوں نے ہماری جماعت سے چالیس سال پہلے کام شروع کیا تھا پھر بھی اب تک صرف چند امراء کی وجہ سے ان کو شہرت حاصل ہوئی ہے جو ان کی جماعت میں شامل ہوئے.لوگوں کی اکثریت نے ان کی طرف کوئی توجہ نہیں کی.اور ان چند امراء کا بہائیت کی طرف میلان بھی کسی قربانی کی وجہ سے نہیں ہوا بلکہ اس وجہ سے ہوا کہ امراء مذہبی پابندیوں کو سخت مصیبت سمجھتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا طریق نکل آئے کہ مذہب بھی رہے اور آزادی بھی ہاتھ سے نہ جائے.اس خیال کے ماتحت اگر انہیں کسی مذہب میں آسانی نظر آتی ہے تو وہ اس میںشوق سے شامل ہو جاتے ہیں.سمجھتے ہیں کہ ہم مذ ہب کے بھی پابند رہیں گے اور ہر قسم کے تعیّش سے بھی کام لیتے رہیں گے.بہائیت میں اس قسم کی کوئی پابندیاں نہیں، وہ کہتے ہیں نماز جس کے پیچھے چاہو پڑھو جو چاہو کرو تمہیں کوئی باز پُرس نہیں ہو گی.نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگ جو بیک وقت مذہب اور آزادی سے ہمکنار رہنا چاہتے ہیں وہ اس مذہب میں شامل ہو جاتے ہیں.
Page 230
میں جب ولایت گیا تو ایک انگریز بہائی عورت مجھ سے ملنے کے لئے آئی اور کہنے لگی آپ بہاء اللہ کو کیوں نہیں مانتے میں نے کہا تم قرآن میں کوئی نقص بتا دو تو پھر یہ سوال بھی ہو سکتا ہے کہ میں کسی اور مذہب کی طرف رجوع کروں ورنہ جب تک قرآن کریم میں کوئی نقص ثابت نہیں ہوتا مجھے کسی اور مذہب کی تعلیم کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے وہ کہنے لگی دیکھئے! قرآن میں یہ کتنا بڑا نقص ہے کہ اس نے ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت دی ہے.میں نے کہا بہاء اللہ نے خود ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت دی ہے، وہ کہنے لگی یہ بات بالکل غلط ہے، بہاء اللہ نے قطعاً ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت نہیں دی.اس کے ساتھ ایک اور عورت بھی تھی جو ایرانن تھی اور چھ ماہ کے قریب مرزا عباس علی کے پاس رہ آئی تھی.میں نے اس انگریز عورت سے کہا کہ تم اپنے ساتھ والی عورت سے پوچھو کہ کیا یہ درست ہے یا نہیں.اس نے پوچھا تو وہ جواب دینے میں کچھ شرارت کر گئی کہنے لگی دو۲ شادیوں کا ذکر تو آتا ہے مگر بہاء اللہ نے لکھا تھا کہ میرے کلام کی جو تشریح مرزا عباس علی کریں وہی درست ہو گی اور انہوں نے یہی تشریح کی ہے کہ ایک ہی شادی کرنی چاہیے.میں نے کہا یہ بھی کوئی معقول بات ہے کہ دو۲شادیوں کا ذکر ہو اور کہا جائے کہ اس سے مراد ایک ہی شادی ہے.انگریز عورت کہنے لگی جواب تو درست ہے کہ جب مرزا عباس علی نے تشریح کر دی اور کہہ دیا کہ ایک ہی شادی کرنی چاہیے تو معاملہ ختم ہو گیا.میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ بہاء اللہ نے عباس علی کو کہا تھا یا نہیں کہ تم لڑکے کی خاطر دوسری بیوی کر لو.اس انگریز عورت نے کہا یہ کبھی نہیں ہو سکتا.میں نے کہا اپنے ساتھ والی سے پوچھو.اس سے پوچھا گیا تو وہ کہنے لگی کہا تو تھا مگر اس نے مانا نہیں.میں نے کہا اس نے بات نہیں مانی تو وہ نافرمان تھا اس پر الزام عائد ہوتا ہے کہ اس نے اپنے باپ کے حکم کی جو مظہرِ خدا تھا خلاف ورزی کی.اس انگریز عورت نے کہا کہ نہیں جب اس نے انکار کر دیا تو بات صاف ہو گئی.بہاء اللہ نے خواہ کچھ لکھا ہو اس نے انکار کر دیا تو پتہ لگ گیا کہ دوسری شادی جائز نہیں.میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ بہاء اللہ کی اپنی دو۲ بیویاں تھیں یا نہیں.انگریز عورت نے پھر کہا کہ ہرگز نہیں.میں نے کہا اپنی ایرانن بہن سے پوچھو.اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں.میں نے کہا آخر تم وہاں رہ آئی ہو اور تمہاری ساتھن ناواقف ہے تمہارا تنا بتا دینے میں کیا حرج ہے کہ بہاء اللہ کی دو۲ بیویاں تھیں یا نہیں.اس نے کہا اصل بات یہ ہے کہ دعویٰ سے پہلے اس کی دو۲ بیویاں تھیں لیکن دعویٰ کے بعد اس نے ایک بیوی کو بہن قرار دے دیا تھا.انگریز عورت یہ سن کر اچھل پڑی اور کہنے لگی دیکھئے دیکھئے!! جواب ہو گیا.میں نے کہا تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ بہاء اللہ خدائی کے مقام پر تھا اور بچپن سے اسے علم غیب حاصل تھا، اگر بہاء اللہ کو علم تھا کہ مجھے اپنی ایک بیوی کو بہن قرار دینا پڑے گا تو اس نے
Page 231
دوسری شادی ہی کیوں کی.انگریز عورت کہنے لگی نہیں جب اس نے ایک کو بہن قرار دیا تھا تو یہ کافی تھا.میں نے کہا اچھا اس ایرانی بہن سے پوچھو کہ کیا بہن سے بچے پیدا کرنے بھی بہائی مذہب میں جائز ہیں.اگر نہیں تو دعویٰ کے بعد اس بہن کے بطن سے بہاء اللہ کے ہاں اولاد کیوں پیدا ہو ئی تھی.اس پر وہ انگریز عورت جوش سے کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی آپ تو گالیاں دینے لگ گئے ہیں.میں نے کہا یہ گالیاں نہیں بلکہ حقیقت کا اظہار ہے.تم اس سے پوچھو کہ کیا دعویٰ کے بعد بہاء اللہ کے ہاں اس دوسری عورت سے اولاد ہوئی ہے یا نہیں.اس دفعہ ایرانن بہت دیر تک خاموش رہی مگر آخر اسے تسلیم کرنا پڑا کہ دوسری بیوی سے دعویٰ کے بعد بھی ان کے ہاں اولاد ہوئی تھی.میں نے کہا اب آپ خود فیصلہ کر لیں کہ ہم قرآن کو کیوں مانتے ہیں اور بہاء اللہ کو اپنے دعویٰ میں کیوں سچا تسلیم نہیں کرتے.بہاء اللہ کو ہم اسی صورت میں مان سکتے تھے جب قرآن کریم کے ذریعہ ہماری دینی ضروریات پوری نہ ہو سکتیں اور بہاء اللہ اس ضرورت کو پورا کر دیتے لیکن اگر وہ ایسا نہیں کر سکتے اور ادھر کوئی ایسی ضرورت بھی نہیں ہے جسے اسلامی شریعت نے پورا نہ کیا ہو تو کوئی وجہ نہیں کہ قرآنی شریعت کو ترک کیا جائے اور بہائی شریعت کو قابلِ قبول قرار دیا جائے.غرض بہائی شریعتِ اسلامیہ کو منسوخ قرار دیتے اور ایک نئی شریعت دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں.مگر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام دنیا میں اس لئے مبعوث ہوئے ہیں کہ آپؑاسلام کو زندہ کریں اور شریعت کو دنیا میں قائم کریں.اللہ تعالیٰ نے خود آپؑکو الہاماً فرمایا کہ یُـحْیِ الدِّیْنَ وَیُقِیْمُ الشَّـرِیْعَۃَ (تذکرہ صفحہ ۵۷۵).مسیح موعود ؑ اس لئے آیا ہے تاکہ وہ اسلام کو زندہ کرے اور شریعت کو دوبارہ دنیا میں قائم کرے.آپؑاس مقصد کو لے کرکھڑے ہوئے اور لاکھوں لوگوں کو اپنے ارگرد اکٹھا کر لیا.بہاء اللہ نے یہی کیا کہ اسلامی شریعت میں سے بہت سی باتوں کو یا منسوخ کر دیا یا ان میں آسانیاں پیدا کر دیں.مگر پھر بھی لوگوں نے اس کو نہ مانا.بہائیوں کی مثال بالکل ایسی ہی ہے جیسے اردو میں کہتے ہیں ’’شافعی سب کچھ معافی‘‘ ان کا مذہب بھی اسی قسم کا ہے.اس قسم کی تحریک کو دنیا میں چلانا اور بات ہے اور ساری دنیا کی مخالفت کے باوجود بنی نوع انسان کی ساری زندگی بدلنا، ان کی صبح بدلنا ان کی شام بدلنا، ان کا دن بدلنا ان کی رات بدلنا، ان کا اوڑھنا بدلنا ان کا بچھونا بدلنا، ان کا کھانا بدلنا ان کا پینا بدلنا، ان کا ظاہر بدلنا ان کا باطن بدلنا، ان کا مذہب بدلنا ان کی سیاست بدلنا، ان کی تعلیم بدلنا اور ان کا تمدن بدلنا یہ وہ کام ہے جسے حقیقی کام کہا جا سکتا ہے اور وہ یہ کام ہے جو گذشتہ دو ہزار سال میں یا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا یا اب ان کے شاگرد حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے کیا ہے.پس ترقی کے جو آثار ہیں وہ صرف حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی جماعت میں پائے جاتے ہیں.آپؑہی دنیا
Page 232
کے مسیحؑ اور مہدؑی ہیں.آپؑہی ان کے نجات دہندہ ہیں اور آپ ہی وہ موعود ہیں جو ان تاریخوں میں ظاہر ہوئے جو محمد رسول اللہصلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی تھیں یا قرآن کریم میں ان کا ذکر آتا تھا.اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ۪ۙ۰۰۷ کیا تجھے معلوم ہے کہ تیرے رب نے عاد سے کیا (معاملہ) کیا.تفسیر.اَلَمْ تَرَ کا مطلب اَلَمْ تَرَ قرآن کریم کا ایک محاورہ ہے اس سے رؤیتِ قلبی یا رؤیتِ علمی مراد ہوتی ہے رویتِ عین مراد نہیں ہوتی جیسے قرآن کریم میں ہی ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَلَمْ تَرَکَیْفَ فَعَلَ رَبُّکَ بِاَصْحٰبِ الْفِیْلِ (الفیل:۲) کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب الفیل کے ساتھ کیسا سلوک کیا حالانکہ اصحاب الفیل کے واقعہ کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے اس کے حالات آپؐنے دیکھے نہیں تھے.پس معنے یہی ہیں کہ کیا تمہیں معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے اصحاب الفیل سے کیا کیا.اسی طرح اَلَمْ تَرَکَیْفَ فَعَلَ رَبُّکَ بِعَادٍ میں بھی رؤیتِ علمی مراد ہے رؤیتِ عین مراد نہیں.مطلب یہ ہے کہ کیا تجھے معلوم نہیں اللہ تعالیٰ نے عاد سے کیا کیا اور کیا تو ان حالات سے نصیحت حاصل نہیں کرسکتا.یہاں تُو سے مراد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ ہر انسان مخاطب ہے.بعض جگہ خطاب واحد کے صیغہ سے ہوتا ہے لیکن مراد ایک جماعت ہوتی ہے.یہاں بھی اَلَمْ تَرَ سے مراد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ سارے مسلمان اور پھر ساری دنیا ہے.عاد ایک قبیلے کا نام تھا اس کا ذکر تفصیلی طور پر تفسیر کبیر جلد ۴ صفحہ ۲۸۱ سورۃ ہود آیت ۵۱ وَ اِلٰى عَادٍ اَخَاهُمْ هُوْدًامیں آچکا ہے.عاد کے وجود کے متعلق بعض لوگوں کا اعتراض اور اس کا جواب یورپین لوگ کہتے ہیں کہ اس قبیلے کا وجود آثارِ قدیمہ سے نہیں ملتا.چنانچہ عرب کے جس قدر کھنڈرات کھودے گئے ہیں اور جس قدر آثار قدیمہ کا سراغ لگایا گیا ہے ان میں عاد کا وجود کسی جگہ نہیں ملا.لیکن ان کی یہ بات ثبوت اور دلیل کے طور پر تسلیم نہیں کی جا سکتی.اوّل تو اس لئے کہ ان کا پرانے کھنڈرات کو تلاش کرنا یہ معنے نہیں رکھتا کہ عرب کے سارے کھنڈرات انہوں نے تلاش کر لئے ہیں.عرب میں انگریزوں کو تو کوئی جانے ہی نہیں دیتا.باہر کے علاقوں میں جہاں ان کا قبضہ ہے انہوں نے کچھ کھنڈرات بے شک تلاش کئے ہیں.لیکن ان کھنڈرات میں عاد کے نشانات کا نہ ملنا یہ معنے نہیں رکھتا
Page 233
کہ انہوں نے سارے کھنڈرات کھود لئے ہیں اور اب کوئی بھی ایسا کھنڈر باقی نہیں رہا جسے تلاش کیا جا سکے.ہندوستان میں انگریز تین سو سال سے حکومت کر رہے ہیں.مگر ہندوستان کے سارے کھنڈرات وہ اب تک نہیں نکال سکے.تیس چالیس سال کی بات ہے کہ ٹیکسلا میں اشوکا کا شہر نکلا جو ہندوستان کے بہت بڑے بادشاہوں میں سے تھا اور اب تک پتہ نہیں چلتا تھا کہ اس کا مقام کہاں تھا.تیس چالیس سال ہوئے وہاں ایک مقام کو جو ’’شاہ دی ڈھیری‘‘ کہلاتا تھا کھودا گیا تو اشوکا کے محلات اور اس کا شہر نکل آیا.حالانکہ اس سے پہلے وہ اشوکا کا صدر مقام کبھی بنگال میں بتاتے تھے.کبھی بہار میں اور کبھی کسی اور جگہ.گویا اس کے حالات اتنے مخفی تھے کہ لوگوں کو یہ بھی معلوم نہیں رہا تھا کہ وہ کہاں رہتا تھا.اتفاقیہ طور پر ایک مقام کو کھودا گیا تو اس میں سے اشوکا کے محلات وغیرہ نکل آئے.حالانکہ وہ ایک زمانہ میں سارے ہندوستان کا بادشاہ تھا.اسی طرح سندھ میں منجودھارو کے مقام پر جسے سندھی زبان میں ’’موہنجو ڈیرو‘‘ کہتے ہیں ایسے آثارِ قدیمہ برآمد ہوئے ہیں جن سے سندھ کی پرانی تہذیب کا پتہ چلتا ہے اور خیال کیا جاتا ہے کہ وہ اشوکا کی تہذیب سے بھی پرانی ہے.سندھیوں کو اس کا کچھ پتہ نہیں تھا.اتفاقاً وہ جگہ کھودی گئی تو نیچے سے ایسے آثار نکل آئے جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ آج سے دس بارہ ہزار سال پہلے کے ہیں.قاعدہ یہ ہے کہ جو بھی جگہ نکلے اس کے متعلق کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ سب سے قدیم تہذیب کے آثار ہیں.تھوڑے ہی دن ہوئے جیکب آباد میں ایک جگہ نکلی ہے اور خیال کیا جاتا ہے کہ وہ اس سے بھی پرانی ہے.پس ایک ایسی جگہ میں بھی جہاں صدیوں سے انگریزوں کی حکومت ہے جب وہ ابھی تک مکمل کھدائی نہیں کر سکے تو عرب کے متعلق یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ وہاں انہوں نے پورے طور پر کھدائی کر لی ہے.پس اوّل تو یہ دعویٰ کہ کھدائی میں عاد کا نام نہیں نکلا اگر صحیح ہو تو اس سے صرف اتنا پتہ چلتا ہے کہ جن کھنڈرات کی یورپین نے کھدائی کی ہے ان میں عاد کا نام نہیں نکلا نہ یہ کہ عاد کا وجود تھا ہی نہیں.اگر چین میں بیٹھا ہوا ایک شخص یہ کہہ دے کہ افریقہ کوئی نہیں تو اس کے معنے صرف اتنے ہی ہوں گے کہ اس نے افریقہ کو نہیں دیکھا نہ یہ کہ افریقہ کا کوئی وجود ہی نہیں.دوسرا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم نے جب عادِارم فرمایا ہے تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ عاد کسی ایک قبیلے کا نام نہیں بلکہ مجموعہ قبائل کا نام تھا اور کئی قسم کے عاد تھے اور جبکہ عاد مجموعۂ قبائل کا نام تھا تو جس قبیلے کی بھی حکومت ہو گی وہ اپنا نام لکھتا ہو گا مجموعے کا نہیں لکھتا ہو گا اس وجہ سے یہ خیال کر لینا کہ پرانے آثار میں عادِ ارم کا نام نہیں ایک مغالطہ ہے.حقیقت یہ ہے کہ جو نام بھی کسی پرانے عرب قبیلے کا نکلے گا اسے عاد کے قبائل میں سے ہی قرار دینا
Page 234
پڑے گا.کیونکہ عربوں کے نزدیک ان کی پرانی تہذیب عاد قوم کی مرہون منت تھی.تیسرا قطعی ثبوت یہ ہے کہ یونانی جغرافیوں میں لکھا ہے کہ یمن میں زمانہ مسیح سے قبل ایک قبیلہ حاکم تھا جس کا نام ’’ایڈرامی ٹائی‘‘ تھا.اور یہ لفظ صاف بتا رہا ہے کہ یہ عادِ ارم کا بگڑا ہوا ہے.یوروپین مصنفوں نے اس خیال کا اظہار کیا ہے کہ اس سے مراد عاد نہیں بلکہ حضر موت ہے مگر یہ خیال غلط ہے.اوّل تو اس لئے کہ ’’ایڈرامی ٹائی‘‘ ایک قبیلے کا نام بتایا گیا ہے اور حضرموت شہر کا نام ہے دوسرے حضر موت کے لئے یونانی جغرافیوں میں ہی ایک علیحدہ لفظ موجود ہے.چنانچہ جس جغرافیہ میں ’’ایڈرامی ٹائی‘‘ کا ذکر آتا ہے اسی جغرافیہ میں حضر موت کا نام ’’ایڈراموٹی ٹائی‘‘ (ADRAMOTITAI) لکھا ہے اور حضر موت کا یہ نام یونانی اور لاطینی دونوں کتب میں مذکور ہے معلوم نہیں یوروپین مصنفین نے ان دو فرقوں کے ہوتے ہوئے جب کہ ایک نام شہر کا ہے اور ایک قوم کا اور ایک کے ہجے اور ہیں اور دوسرے کے اور.دونوں کو ایک کس طرح قرار دے دیا.’’ایڈرامی ٹائی‘‘ کا لفظ جو عادِ ارم کے متعلق آتا ہے اصل میں ’’ایڈرامی ٹائی‘‘ ہے ٹائی جو آخر میں آتا ہے وہ یونانی میں نام کی علامت ہوتی ہے اور ظاہر ہے کہ ایڈ عاد ہے اور رامی ارم ہے اور اس نام سے ملتا ہوا کوئی قبیلہ عرب کا سوائے عاد ارم کے نہیں ہے ایک مشہور عیسائی مؤرخ اپنی تاریخ میں لکھتا ہے کہ عاد کے متعلق مؤرخوں کی سینکڑوں صفحوں کی کتابیں اس سے زیادہ معلومات بیان نہیں کر سکیں جتنے معلومات قرآن کریم نے اپنے چند الفاظ میں بیان کر دیئے ہیں.جس قدر قدیم روایات اس سلسلہ میں بیان کی جاتی ہیں ان کو دیکھنے کے بعد انسان صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہے کہ پرانی تاریخوں میں عاد ارم کے متعلق جس قدر باتیں بیان کی گئی ہیں وہ سب کی سب لغو اور فضول ہیں سوائے اس حصہ کے جو قرآن کریم نے بیان کیا ہے.یہ عیسائی مؤرخ شدید دشمنِ اسلام ہے مگر عاد ارم کی تاریخ کے متعلق قرآن کریم کی فضیلت کا اقرار کرنے پر مجبور ہو گیا ہے (دیکھو العرب قبل الاسلام مصنفہ جرجی زیدان الجزء الاوّل صفحہ۶۳،۶۴) قرآن مجید میں عاد کے حالات قرآن کریم سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ قبیلہ بہت طاقتور تھا چنانچہ اگلی آیت میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَمْ یُخْلَقْ مِثْلُھَا فِی الْبِلَادِ اس زمانہ تک اتنی طاقت کی کوئی قوم دنیا میں پیدا نہیں ہوئی تھی.قرآن کریم سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ احقاف میں رہتے تھے.احقاف کے عرب میں دو علاقے ہیں ایک وہ علاقہ ہے جو جنوبی احقاف کہلاتا ہے یہ یمن سے شروع ہو کر صنعاء کے نیچے نیچے عدن سے اوپر مشرق کی طرف کو چلا گیا ہے پھر وہاں سے پھیلتا ہوا شمال کی جانب کو نکل گیا ہے.دوسرا علاقہ شمالی احقاف ہے جو بصریٰ سے
Page 235
نیچے کی طرف عراق کے بیابان کے ساتھ ساتھ چلا جاتا ہے.غرض احقاف نے عرب کو گھیرا ہوا ہے ایک نیچے کے احقاف ہیں اور ایک اوپر کے درمیان میں نجد اور حجاز کے علاقے ہیں.احقاف ان ریت کے ٹیلوں کو کہتے ہیں جو اونچے نیچے خم کھاتے ہوئے گذر جاتے ہیں.قرآن کریم سے پتہ لگتا ہے کہ یہ لوگ وہاں رہتے تھے جہاں اب احقاف ہیں.جیسا کہ فرماتا ہے وَاذْكُرْ اَخَا عَادٍ١ؕ اِذْ اَنْذَرَ قَوْمَهٗ بِالْاَحْقَافِ (الاحقاف:۲۲) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کا زور شمالی اور جنوبی عرب میں تھا یا وہ علاقے جو شمالی اور جنوبی احقاف کہلاتے ہیں ان میں ان لوگوں کا زور تھا.تاریخوں میں جو مختلف روایات آتی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ جنوب سے پھیل کر شمال میں چلے گئے تھے اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ ثمود قوم جو عاد کا ایک قبیلہ تھی اس کے آخری دَور میں اس کی حکومت شمالی عرب اور جنوبی فلسطین میں تھی اور یہیں اس کے آثار ملتے ہیں.چنانچہ حجر بھی ان کا ایک شہر ہے جو مدینہ منورہ اور تبوک کے درمیان ہے.یہ قوم حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ہوئی ہے چنانچہ قرآن کریم میں ان کے نبی کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ وَاذْكُرُوْۤا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْۢ بَعْدِ قَوْمِ نُوْحٍ (الاعراف:۷۰) یعنی یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تم کو نوحؑکی قوم کے بعد دنیا میں غلبہ عطا کیا.پس اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نوحؑکے ساتھ براہ راست جس قوم کا تعلق تھا اورجس نے قوم نوحؑکے بعد عرب میں غلبہ حاصل کیا وہ عاد لوگ تھے.عاد کے متعلق قرآن مجیدکی پیشگوئی اور اس کا ظہور تورات میں جو بابل کی تباہی کا ذکر ہے اور جو قومِ نوحؑکی تباہی تھی معلوم ہوتا ہے اس تباہی کے بعد جو اقوام بابل سے نکل کر پھیلیں ان میں سے ایک قبیلہ جس نے بعد میں ترقی کی اس کا نام عاد تھا.یہ قبیلہ نسلاً بڑا مضبوط اور جلد جلد پھیلنے والا تھا.چنانچہ قرآن کریم میں حضرت ہود علیہ السلام ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصْۜطَةً (الاعراف:۷۰) یہاں پیدائش کے معنے نسل کے بھی ہیں اور جسم کی بناوٹ کے بھی.اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ قد آور جوان تھے اور ان کی نسل خوب ترقی کرتی تھی.اس بنا پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ عمالقہ کی نسلیں جو عرب کے شمال میں تھیں وہ انہی لوگوں کے بقایا میں سے تھیں.پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس قبیلہ میں شرک کا مرض بھی کثرت سے تھا.چنانچہ حضرت ہود علیہ السلام کہتے ہیں يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ(الاعراف:۶۶) اے میری قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اس کے سوا
Page 236
تمہارا کوئی معبود نہیں.اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ قوم شرک میں مبتلا تھی.حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بھی چونکہ شرک میں مبتلا تھی اس لئے معلوم ہوتا ہے وہی روایات ان میں بھی آ گئیں.پھر یہ لوگ بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے چنانچہ اسی سورۂ فجر میں ان کو ذات العماد کہا گیا ہے جس کے معنے یہ ہیں کہ و ہ لوگ بڑی بڑی اونچی عمارتیں بنانے والے تھے.پھر قرآن کریم میںیہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان کی تباہی ایک آندھی سے ہوئی تھی جو سات راتیں اور آٹھ دن متواتر ان پر چلتی رہی.اور پھر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ لوگ اس طرح تباہ و برباد کر دیئے گئے کہ قومی طور پر ان کا کوئی نشان باقی نہیں رہا چنانچہ فرماتا ہے فَاَصْبَحُوْا لَا يُرٰۤى اِلَّا مَسٰكِنُهُمْ (الاحقاف:۲۶) ان کی قوم کا نشان بالکل مٹ گیا ہے صرف ان کی بڑی بڑی عمارتوں کے آثار باقی رہ گئے ہیں.دیکھو یہ بھی کیسی زبردست پیشگوئی ہے جو پوری ہوئی.یوروپین مؤرخ اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمیں عاد کا کہیں نام نہیں ملتا اور وہ اتنا نہیں سوچتے کہ قرآن کریم نے تو خود کہہ دیا تھا کہ فَاَصْبَحُوْا لَا يُرٰۤى اِلَّا مَسٰكِنُهُمْ (الاحقاف:۲۶) صرف عمارتیں نظر آئیں گی.ان کا نام نظر نہیں آئے گا کیونکہ ہم نے ان کا نام بالکل مٹا دیا ہے پس اگر انہوں نے یہ نئی تحقیق کی ہے کہ عاد کا نام آثار قدیمہ میں نہیں ملتا تو ہم کہتے ہیں اس سے بھی قرآن کریم کی صداقت ہی ثابت ہوتی ہے کیونکہ قرآن کریم نے خود کہا تھا کہ آثار قدیمہ کی تلاش و جستجو کے بعد ان کی عمارتیں تو ٹوٹی پھوٹی تمہیں مل جائیں گی مگر ان کا نام نہیں ملے گا.پس یہ جملہ قرآن کریم کی صداقت کو باطل ثابت کرنے والا نہیں بلکہ اس کی اور بھی تائید کرنے والا ہے.عاد قوم کے نبی حضرت ہودؑ تھے ان کا ذکر قرآن کریم (میں) ستر۱۷ہ جگہ پر آیا ہے.(۱)ہود.اس میں چار جگہ نام آتا ہے.(۲)شعراء (۳) قمر (۴) فُصِّلَتْ (۵) اعراف (۶)فجر (۷)ذاریات (۸)ص (۹)ق (۱۰) توبہ (۱۱)ابراہیم (۱۲)حج (۱۳)مومن (۱۴) نجم (۱۵)فرقان (۱۶)عنکبوت (۱۷) احقاف.سورۂ فُصّلت میں دو دفعہ اور ہود میں چار دفعہ ذکر آتا ہے اس طرح سارے قرآن کریم میں ان کا ۲۱ دفعہ ذکر ہو گیا.میں ان قرآنی حالات کے متعلق ایک عیسائی مؤرخ کا قول پہلے بیان کر چکا ہوں کہ ان حالات سے زیادہ مکمل اور صحیح حالات ہمیں دنیا کی اور کسی تاریخ سے نہیں مل سکتے.
Page 237
اِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ۪ۙ۰۰۸ یعنی (عاد) ارم سے جو بڑی بڑی عمارتوں والے تھے.حلّ لُغات.اَلْعِمَادُ.اَلْعِمَادُ کے معنے ہیں اَلْاَ بْنِیَۃُ الرَّفِیْعَۃُ اونچی عمارتیں.اس کا مفرد عِـمَادَۃٌ آتا ہے (اقرب) پس ذَاتِ الْعِمَادِ کے معنے ہوئے.بلند اور اونچی عمارتوں والا قبیلہ.تفسیر.ارم عطفِ بیان ہے عاد کے بعد.ارم کے متعلق تین مختلف خیالات پائے جاتے ہیں.بعض لوگ کہتے ہیں کہ ارم قبیلے کا نام ہے اور یہاں ارم قبیلہ سے تعلق رکھنے والے عاد کا ہی ذکر کیا گیا ہے بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ قبیلے کا نام نہیں بلکہ ایک شہر کا نام ہے.وہ لوگ بِعَادٍ اِرَمَ کی بجائے بِعَادِ اِرَمَ پڑھتے ہیں یعنی وہ عاد جو ارم جگہ کے رہنے والے تھے.بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ ہے تو شہر کا نام مگر مراد ہے اِرَمَ صَاحِبِ ذَاتِ الْعِمَادِ یعنی ارم جو بڑی عمارتوں والے تھے.قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ اس قبیلہ کے لوگ بڑی بڑی عمارتیں بنایا کرتے تھے چنانچہ سورۂ شعراء میں حضرت ہودؑ ان کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں اَتَبْنُوْنَ بِكُلِّ رِيْعٍ اٰيَةً تَعْبَثُوْنَ.وَ تَتَّخِذُوْنَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُوْنَ (الشعراء:۱۲۹،۱۳۰) یعنی تم لوگ ہر پہاڑی پر شاندار عمارتیں بناتے ہو اور بڑے بڑے کارخانے تیار کرتے ہو اور خیال کرتے ہو کہ تم حوادثِ روزگار سے ہمیشہ محفوظ رہو گے اور کبھی دنیا سے مٹ نہیں سکو گے.یہ اس قبیلہ کی ایک امتیازی خصوصیت تھی جس کا قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے.الَّتِيْ لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ۪ۙ۰۰۹ وہ جن کی مثل (قوم) ان ملکوں میں پیدا ہی نہ کی گئی تھی.تفسیر.لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ کا مطلب لَمْ یُخْلَقْ مِثْلُھَا فِی الْبِلَادِ سے مراد یہ ہے کہ اس قوم سے پہلے اور کوئی قوم اس جیسی طاقتور نہیں گذری.قرآن کریم میں مختلف مقامات پر مختلف رنگ میں اس قسم کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں جن کو دیکھ کر بعض لوگ اعتراض کر دیا کرتے ہیں کہ ساری قوموں یا سارے لوگوں کے متعلق یہ کس طرح کہا جا سکتا ہے کہ ان کی کوئی مثال نہیں پائی جاتی.ایک قوم تو ایسی ہو سکتی ہے جو
Page 238
بےمثال ہو لیکن ہر قوم کے متعلق یہ کس طرح کہا جا سکتا ہے کہ اس جیسی پہلے کوئی قوم نہیں گذری.اس اعتراض کے متعلق یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ طاقت وقوت میں مقابلہ کبھی ایک ملک سے ہوتا ہے اور کبھی ایک قوم سے.اور کبھی ساری دنیا سے.اگر بالکل ابتدائی زمانہ ہو اور اس وقت کسی قوم کے متعلق یہ کہا جائے کہ لَمْ یُخْلَقْ مِثْلُھَا فِی الْبِلَادِ تو اس سے مراد صرف یہ ہو گی کہ اس سے پہلے اور کوئی قوم اتنی بڑی طاقت حاصل نہیں کر سکی اور اگر مختلف قومیں دنیا میں پھیل چکی ہوں اور مختلف ممالک میں مختلف قومیں حکومتیں کر رہی ہوں تو اس وقت اس قسم کے الفاظ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس ملک میں اس سے بڑی طاقت اور کوئی نہیں تھی گویا یہ الفاظ محض نسبتی ہوتے ہیں کلّی فضیلت مراد نہیں ہوتی.انسان کا اپنا فرض ہوتا ہے کہ وہ عقل سے کام لے اور صحیح معنوں کی تعیین کرے.ہاں ایمانیات کا معاملہ اس سے مختلف ہے وہاں ایسے قرائن بھی رکھ دیئے جاتے ہیںجن سے اس نتیجہ پر پہنچنے میں آسانی ہو جاتی ہے کہ کسی جزوی فضیلت کا ذکر کیا جا رہا ہے یا کلّی فضیلت کا.مثلاً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے زمانوں کے لئے ہیں اور آپ قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے مطاع اور پیشوا ہیں یہ بات چونکہ ایمانیات سے تعلق رکھتی تھی اور ہر وہ شخص جو آپ کی اس فضیلت پر ایمان نہ لاتا روحانی لحاظ سے سخت مجرم اور گناہ گار سمجھا جاتا.اس لئے جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمگیر بعثت کا ذکر کیا گیا وہاں ایسے قرائن بھی رکھ دیئے گئے جن سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ سارے زمانوں اور سارے ملکوں کے لئے ہیں آپ کی نبوت سابق انبیاء کی طرح مختص الزمان نہیں ہے لیکن جہاں کسی قوم کی صرف ظاہری طاقت اور شوکت کا اظہار ہو وہاں ہر معقول انسان کا فرض ہے کہ وہ خود اندازہ لگائے اور سوچے کہ یہ نسبتی الفاظ ہیں یا کلّی.جیسے قرآن کریم ہمیشہ ذومعانی الفاظ استعمال کرتا ہے لیکن عقل مند انسان دیکھ لیتا ہے کہ اس عبارت میں کون سے معنے چسپاں ہوتے ہیں اور کون سے نہیں.بسا اوقات چار میں سے دو معنے چسپاںہو تے ہیں اور دو نہیں ہوتے.اس وقت انسان خود ہی فیصلہ کر لیتا ہے کہ یہ یہ معنے یہاں چسپاں ہوسکتے ہیں.قرآن کریم صرف اسی جگہ قرائن مرجّح رکھتا ہے جہاں معنوں میں ادنیٰ غلطی ایمان میں خرابی پیدا کر دیتی ہو.جیسے فرمایا تھا وَالسَّمَآءِ وَالطَّارِقِ.اب طارق کے لفظ سے ایک شبہ پیدا ہو سکتا تھا جس کا مَاۤ اَدْرٰىكَ مَا الطَّارِقُ کہہ کر ازالہ کیا.کیونکہ طارق کے دو معنے ہیں ایک معنے ہیں رات میں آنے والا اور دوسرے معنے ہیں صبح کا ستارہ.چونکہ گذشتہ سورتوں سے ایک نبی کے آنے کی پیشگوئی بیان ہو رہی تھی اس لئے ضروری تھا کہ اس کی حیثیت پر روشنی ڈالی جاتی اور بتایا جاتا کہ اس کی حیثیت رات میں آنے والے کی سی ہے یا صبح کے ستارے کی سی.سو اس کے بعد وَمَاۤ اَدْرٰىكَ مَا الطَّارِقُ.النَّجْمُ الثَّاقِبُ کہہ کر بتا دیا کہ یہاں کوئی اور معنے مراد نہیں بلکہ صرف
Page 239
النَّجْمُ الثَّاقِبُ والے معنے مراد ہیں.یہ قرآن کریم کا دستور ہے کہ وہ جہاں معنوں کی تعیین کرنا چاہتا ہے مَاۤ اَدْرٰىكَ کے الفاظ لے آتا ہے لیکن دوسرے مقامات پر انسان کو مختلف معنوں کی اجازت ہوتی ہے.اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم تمہاری عقل پر اعتبار کرتے ہیں عقل سے کام لو اور صحیح معنے کرو.پس جہاں مختلف معانی سے کوئی خلل پیدا نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ بھی کوئی تعیین نہیں کرتا لیکن جہاں کسی خلل کا امکان ہو وہاں اللہ تعالیٰ اپنے مخصوص معنے بتا دیتا ہے جیسے اَلْقَارِعَۃُ.مَاالْقَارِعَۃُ کے بعد وَمَاۤ اَدْرٰىكَ مَاالْقَارِعَۃُ کہہ کر بتا دیا کہ قارعہ کے اگرچہ لغت میں کئی معنے ہیں لیکن ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ اس جگہ ان کئی معنوں میں سے صرف فلاں معنے مراد ہیں دوسرے معنے کرنے جائز نہیں ہیں.غرض جہاں شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی یا ایمانیات میں کوئی نقص واقعہ ہونے کا احتمال نہیں ہوتا قرآن کریم آیات کے معانی کو محاورۂ زبان اور عقل صحیح پر چھوڑ دیتا ہے.لَمْ یُخْلَقْ مِثْلُھَا فِی الْبِلَادِ میں بھی کوئی ایسی بات نہیں جس کی کسی خاص پیشگوئی یا ایمانیات پر زد پڑتی ہو اس لئے قرآن کریم نے عمومیت کے رنگ میں یہ ذکر کر دیا ہے کہ وہ لوگ بڑی طاقت والے تھے.اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اپنی عقل اور تاریخی معلومات کی بنا پر فیصلہ کریں کہ یہ بات اس وقت کے زمانہ کے لحاظ سے کہی گئی ہے یا ساری دنیا کے لحاظ سے.عاد چونکہ بالکل ابتدائی زمانہ میں ہوئے ہیں اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں ساری دنیا کے مقابلہ میں ان کی فوقیت کا ذکر نہیں کیا گیا بلکہ صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ اپنے زمانہ کے لحاظ سے یا عرب کے لحاظ سے ان جیسی طاقتور قوم اور کوئی نہ تھی.یہ قرآن کریم کی ایک خاص خوبی ہے کہ اس میں کئی تشریحات کو انسانی عقل پر چھوڑا گیا ہے تا کہ دماغی انحطاط واقعہ نہ ہو.قرآن کریم لوگوں کو جاہل نہیں بناتا بلکہ جہاں کسی شبہ کا امکان ہو صرف اس کا ازالہ کرتا ہے اور جہاں ایمانیات میں کسی خطرہ کا امکان ہو اس کو پوری طرح ظاہر کر دیتا ہے تاکہ لوگ ٹھوکر نہ کھائیںاور ان کا ایمان محفوظ رہے.وَ ثَمُوْدَ الَّذِيْنَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ۪ۙ۰۰۱۰ اور کیا ثمود کے متعلق بھی تجھے معلوم ہے ٭ جو وادی (القریٰ) میں پہاڑیوں کو کھودتے تھے.حلّ لُغات.جَابُوْا.جَابُوْا: جَابَ سے جمع کا صیغہ ہے اور جَابَ الثَّوْب (یَـجُوْبُہٗ جَوْبًا) کے ٭نوٹ: ترجمہ میں ’’کیا تجھے معلوم ہے ‘‘کے الفاظ حسب قاعدہ بریکٹ میں نہیں رکھے گئے بلکہ ظاہر میں رکھے گئے ہیں کیونکہ اس کے بغیر اردو میں مفہوم واضح نہیں ہوسکتا تھا.
Page 240
معنے ہوتے ہیں قَطَعَہٗ.اس نے کپڑے کو پھاڑا.اور جَابَ الصَّخْرَۃَ کے معنے ہوتے ہیں خَرَقَھَا.اس نے پتھر کو کھودا.وَمِنْہُ فِی الْقُرْاٰنِ وَثَـمُوْدَ الَّذِیْنَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ اَیْ قَطَعُوْہُ وَاتَّـخَذُوْہُ مَنَازِلَ یعنی قرآن کریم میں جو یہ آتا ہے کہ وَثَـمُوْدَ الَّذِیْنَ جَابُوْا الصَّخْرَ بِالْوَادِ (اقرب) اس کے معنے یہ ہیں کہ وہ پتھروں کو تراش کر یا ان کو کاٹ کاٹ کر عمارتیں بناتے تھے گویا اس آیت کے دونوں معنے ہو سکتے ہیں.یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ چٹانوں کو کاٹ کاٹ کر پتھر لاتے اور اپنے لئے پتھروں کی عمارتیں بناتے اور یہ بھی معنے ہوسکتے ہیں کہ وہ پتھریلی چٹانوں کو کاٹ کاٹ کر ان میں عمارتیں تیار کیا کرتے تھے.اَلصَّخْرُ.اَلصَّخْرُ: اَلصَّخْرَۃُ کی جمع ہے اور اَلصَّخْرَۃُ کے معنے ہیں اَلْـحَجَرُ الْعَظِیْمُ الصُّلْبُ.ایسا بڑا پتھر جو سخت بھی ہو (اقرب) پس اَلَّذِیْنَ جَابُوْا لصَّخْرَ بِالْوَادِ کے معنے ہوئے وہ لوگ جنہوں نے پہاڑ کاٹ کر اور پتھر اکٹھے کر کر کے وادی میں اپنے مکان بنائے یا پہاڑی وادی میں انہوں نے پہاڑوں کو تراش تراش کر عمارتیں بنائیں.تفسیر.ثمود قوم کی خصوصیت ثمود قوم کی یہ خصوصیت تھی کہ وہ پہاڑوں کو تراش تراش کر اپنے لئے عمارتیں بنایا کرتی تھی.اس قوم کا دارالحکومت حجر تھا جو مدینہ منورہ اور تبوک کے درمیان ہے اور اس وادی کو جس میں حجر واقعہ ہے وادیٔ قریٰ کہا جاتا ہے.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوۂ تبوک پر جا رہے تھے اور ہزاروں صحابہؓ آپ کے ساتھ تھے.چلتے چلتے راستہ میں حجر شہر آیا اور وہاں تھوڑی دیر کے لئے آپ نے پڑاؤ کیا.صحابہؓ نے یہ دیکھا تو انہوں نے اپنے آٹے نکالے اور گوندھ کر کھانا پکانے لگ گئے.ابھی تھوڑی دیر ہی گذری تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں خدا تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تھا اس لئے یہاں کا پانی کوئی نہ پئے اور نہ کسی اور مصرف میں لائے چنانچہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں.عَنِ ابْنِ عُـمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ لَمَّا نَزَلَ الْـحِجْرَ فِی غَزْوَۃِ تَبُوْکَ اَمَرَھُمْ اَنْ لَّایَشْـرَبُوْا مِنْ بِئْرِھَا وَلَا یَسْتَقُوْا مِنْـھَا فَقَالُوْا قَدْ عَـجَنَّا مِنْـھَا وَاسْتَقَیْنَا فَاَمَرَھُمْ اَنْ یَّطْرَحُوْا ذٰلِکَ الْعَجِیْنَ وَیُـھْرِیْقُوْا ذٰلِکَ الْمَاءَ (الصحیح البخاری کتاب احادیث الانبیاء باب قول اللہ عز وجل وَ اِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صٰلِحًا) یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم غزوۂ تبوک کو جاتے ہوئے حجر مقام پر اترے تو آپ نے صحابہ کو حکم
Page 241
دے دیا کہ نہ تو وہاں کے کنوؤں کا پانی خود پئیں اور نہ پینے کے لئے ساتھ لیں.تو لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم نے تو اس پانی سے آٹے گوندھ لئے ہیں اور پانی بھی لے لیا ہے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم نے گوندھے ہوئے آٹے کو پھینکوانے اور جمع شدہ پانی کو گرانے کا حکم دے دیا.آنحضرتؐکا ثمود کے مقام پر اترنا دیکھو اللہ تعالیٰ کے انبیاء خدا تعالیٰ کے غضب سے کس قدر ڈرا کرتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ وہ لوگ مر گئے جن پر غضب نازل ہوا تھا اور وہ شہر اجڑ گیا جو اس غضب کا نشانہ بنا تھا.سالوں کے بعد سال اور صدیوں کے بعد صدیاں گذرتی چلی گئیں مگر اس قدر مدت دراز گذرنے کے باوجود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت تھی کہ وہ آج بھی اس مقام پر خدا تعالیٰ کا غضب نازل ہوتے دیکھ رہے تھے آج بھی اس مقام پر خدا تعالیٰ کے فرشتوں کو لعنت کرتے دیکھ رہے تھے آپ نے اتنا بھی پسند نہ کیا کہ اس جگہ کے پانی سے گندھا ہوا آٹا صحابہ استعمال کریں.آپ نے فوراً حکم دیا کہ اپنے گندھے ہوئے آٹے کو پھینک دو، سواریوں پر چڑھ جاؤ اور فوراً اس مقام سے نکل جاؤ کہ یہ وہ مقام ہے جو خدا تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بنا تھا.اسی طرح جہاں خدا تعالیٰ کی رحمت کا کوئی نشان نازل ہو انبیاء ان مقامات کا نہایت ادب کرتے ہیں اور جب بھی ان جگہوں میں جاتے ہیں ان کے دلوں پر خدا تعالیٰ کی خشیت طاری ہو جاتی ہے اور سوائے خدا تعالیٰ کی ذات کے وہ کسی اور طرف توجہ نہیں کرتے.اس کے مقابلہ میں لوگوں کی یہ حالت ہوتی ہے کہ نہ خدا تعالیٰ کے غضب کے نشانات ان کے دلوں کو نرم کرتے ہیں اور نہ اس کی رحمت کے نشانات ان کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کرتے ہیں.مثلاً مساجد خدا کا گھر کہلاتی ہیں اور مساجد وہ مقام ہیں جو خدا تعالیٰ کی عبادت کے لئے مخصوص ہیں مگر لوگ جب مساجد میں آتے ہیں تو وہ ہزار قسم کی بکواس کرتے ہیں، آپس میں دنیوی معاملات پر لڑتے جھگڑتے ہیں، ایک دوسرے کو جوش میں گالیاں بھی دے دیتے ہیں، غیبت بھی کر لیتے ہیں اور انہیں ذرا بھی یہ احساس نہیں ہوتاکہ وہ خدا کے گھر میں بیٹھ کر کس قسم کی شرمناک حرکات کر رہے ہیں.انہیں تو چاہیے تھا کہ وہ جب تک مساجد میں رہتے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ان کی زبانیں تر رہتیں مگر وہ بجائے ذکر الٰہی کرنے کے دنیوی امور میں اپنے قیمتی وقت کو ضائع کر کے خدا تعالیٰ کی ناراضگی کے مرتکب بن جاتے ہیں تم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھو اور غور کرو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا تعالیٰ کے غضب کے مقام کو کتنا برا جانا اور کس طرح اس سے نفر ت کا اظہار کیا کہ گندھا ہوا آٹا پھینکوا دیا اور یہ پسند نہ کیا کہ اس آٹے کا ایک لقمہ تک کسی صحابی کے اندر
Page 242
جائے حالانکہ وہ ایام سخت تنگی کے تھے.صحابہ کی مالی اور اقتصادی حالت سخت کمزور تھی.خود صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہم بعض دفعہ کھجوروں کی گٹھلیاں کھا کھا کر گذارہ کیا کرتے تھے(مسلم کتاب الصید و الذبائح باب اباحۃ میتات البحر ).اس تنگی کے باوجود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منوں آٹا پھینکوا دیا اور اس بات کی ذرا بھی پرواہ نہ کی کہ لشکر کا کیا بنے گا.اس غزوہ میں تین ہزار صحابی آپ کے ساتھ تھا.اگر فی کس ایک پاؤ آٹے کا بھی اندازہ لگایا جائے تو قریباً آٹھ سو سیر یا بیس من کے قریب آٹا ایسے زمانہ میں جب کہ ان کے پاس کھانے پینے کے وافر سامان نہیں ہوا کرتے تھے حُکماً پھینکوا دیا گیا.یہ ہے وہ خشیت جو لوگوں کے دلوں میں ہونی چاہیے اور جس کا اسلام ہر مومن سے تقاضا کرتا ہے.مگر مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ خود ہماری جماعت میں سے بعض لوگوں کی یہ حالت ہے کہ جب وہ مقبرہ بہشتی میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے مزار پر دعا کرنے کے لئے جاتے ہیں تو ان میں سے بعض درختوں کا پھل توڑ کر کھانے لگ جاتے ہیں.گویا بجائے اس کے کہ مقبرہ بہشتی میں جا کر ان کے دلوں میں خدا کا خوف پیدا ہواور دعا پر وہ زور دیں کھانے پینے کا خیال ان کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے.اسی طرح مساجد میں اس قسم کی باتیں ہوتی ہیںاور اس قدر شور بعض لوگوں نے مچایا ہوا ہوتا ہے کہ تعجب آتا ہے کیوں ابھی تک لوگوں کو اتنی موٹی بات بھی معلوم نہیں ہوئی کہ انہیں مساجد کا احترام کرنا چاہیے اور لغو باتوں کی بجائے ذکر الٰہی میں اپنا وقت گذارنا چاہیے.مومن کے ایمان کی سچی علامت یہی ہے کہ جب وہ کسی ایسے مقام سے گذرے جو خدا تعالیٰ کے کسی عذاب کو یاد دلانے والا ہو تو وہاں اس کے اعضاء اور جوارح سے کسی قسم کی بےباکی ظاہر نہ ہوتی ہو.بلکہ اللہ تعالیٰ کا خوف اور اس کی خشیت اس دل پر طاری ہواور وہ اس عذاب کو اپنی آنکھوں سے اس طرح دیکھ رہا ہو جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر میں اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتے دیکھا.اسی طرح جب وہ مسجد میں آئے یا کسی ایسی جگہ جائے جہاں خدا تعالیٰ نے اپنا کوئی نشان ظاہر کیا ہو تو وہاں فضول اور لغو باتیں نہ کرے بلکہ ذکر الٰہی اور خدا تعالیٰ کی یاد کرے.نمازیں پڑھے دعاؤں میں مشغول رہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل کو زیادہ سے زیادہ جذب کرنے کی کوشش کرے یا اگر باتیں ہی کرنی ہوں تو دین کی باتیں کرے.جیسے ہم اپنی مساجد میں جب بیٹھتے ہیں تو ہمیشہ دین کی باتیں کرتے ہیں یا ایسی دنیوی باتیں بھی کر لیتے ہیں جو دین سے تعلق رکھتی ہیں مگر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مساجد میں بیٹھ کر سودا سلف کی باتیں شروع کر دی جائیں یا گھر کے جھگڑے بیان ہونے لگ جائیںیا ایک دوسرے کی غیبت شروع ہو جائے یہ ساری باتیں سخت معیوب ہیں اور انسان کو خدا تعالیٰ کی نظر میں گناہ گار بنادیتی
Page 243
ہیں.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نمونہ کو ہر وقت اپنے سامنے رکھو کہ آپ حجر مقام پر اترے مگر تھوڑی دیر کے بعد گھبرا کر کھڑے ہو گئے اور اپنے صحابہؓ سے فرمایا کہ چلو یہاں سے یہ وہ مقام ہے جہاں خدا کا عذاب نازل ہوا تھا.ثمود قوم کے نبی ثمود قوم کے نبی حضرت صالحؑ تھے.صالح عربی زبان کا لفظ ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صالح عرب کے ہی ایک نبی تھے.قرآن کریم سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ یہ لوگ عاد کے بعد ہوئے ہیں.چنانچہ فرماتا (ہے) وَ اذْكُرُوْۤا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْۢ بَعْدِ عَادٍ (الاعراف:۷۵) اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں عاد کے بعد ان کا قائم مقام بنایا.اس سے یہ بھی استدلال ہوتا ہے کہ عاد بھی عرب ہی تھے.ثمود کے متعلق کتبوں کی دستیابی آثار قدیمہ کی تلاش و جستجو کے سلسلہ میں قوم ثمود کے کتبے بھی دستیاب ہوئے ہیں اور یوروپین لوگوں نے ان کتبوں کو تسلیم کیا ہے یہ کتبے عرب کے شمالی حصوں سے ملے ہیں جس سے ان عرب جغرافیہ نویسوں کی تائید ہوتی ہے جن کا یہ خیال ہے کہ ثمود قوم جنوب سے ہجرت کر کے شمال کی طرف آئی تھی یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ کچھ مصر کی طرف بھی بڑھے تھے.بہرحال قومِ ثمود عاد کے بعد ہوئی ہے اور جب کہ عاد کو نوحؑکی قوم کا قائم مقام قرار دیا گیا ہے تو اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ حضرت نوحؑ بھی عرب کے کسی علاقہ میں ہی مبعوث ہوئے تھے اور پھر اس سے عربی زبان کے ام الالسنہ ہونے کا بھی ایک ثبوت مل گیا.عربی کے اُم الالسنہ ہونے کا ایک ثبوت قرآن کریم دعویٰ کرتا ہے کہ ابتدائی زبان عربی تھی اور یہی زبان باقی تمام زبانوں کی اُم ہے یہ علیحدہ بات ہے کہ دشمن اس بات کو تسلیم نہ کرے لیکن قرآن کریم یہی کہتا ہے کہ ابتدائی نسل کی زبان عربی تھی.اس کا ثبوت اس امر سے بھی ملتا ہے کہ قرآن کریم حضرت نوحؑکو آدم کے معاً بعد قرار دیتا ہے.اب اگر نوحؑتک یہ سلسلہ پہنچ جائے اور ثابت ہو جائے کہ حضرت نوحؑعربی نسل سے تعلق رکھتے تھے تو ساتھ ہی عربی زبان کے اُم الالسنہ ہونے کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے.یہ بات بتائی جا چکی ہے کہ قوم ثمود، عاد کی قائم مقام تھی اور عاد، نوحؑکی قوم کی قائم مقام تھی اور چونکہ ثمود اور عاد دونوں عربی اقوام ہیں اس لئے معلوم ہوا کہ حضرت نوحؑبھی عرب کے کسی علاقہ میں ہی مبعوث ہوئے تھے اور تاریخ سے بھی حضرت نوحؑکا مقام عراق میں ہی ثابت ہوتا ہے جب حضرت نوحؑتک یہ زبان پہنچ گئی تو نوحؑکے متعلق اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ وہ آدمؑ کے معاً بعد ہوئے بتاتا ہے کہ ابتدائے عالم کی زبان عربی تھی کیونکہ جب نسل انسانی کا آغاز عرب سے مانا جائے تو لازماً اس ملک کی زبان کو بھی اُم الالسنہ تسلیم کرنا پڑے گا بہرحال عرب اور اس کے متعلقہ علاقہ سے ابتدائے تہذیب کے وابستہ ہونے کا دعویٰ ان آیات سے مستنبط ہوتا ہے اور
Page 244
تاریخی واقعات اس دعویٰ کی تائید کرتے ہیں.ثمود کا ذکر قرآن کریم میں ۲۱ جگہ آیا ہے.(۱) ہود (۲) شعراء (۳) قمر (۴) حاقہ(۵) شمس (۶) بنی اسرائیل (۷) اعراف (۸) نمل (۹) فُصِّلت (۱۰) ذاریات (۱۱) توبہ (۱۲) ابراہیم (۱۳) حج (۱۴) مومن (۱۵) ص (۱۶) فرقان (۱۷) عنکبوت (۱۸) ق (۱۹) فجر (۲۰) بروج (۲۱)نجم (ثمود اور صالحؑ اور ان کے واقعہ کے لئے دیکھئے تفسیر کبیر جلد چہارم صفحہ۲۹۳ تا ۳۰۷ زیر تفسیر سورۃ ہود آیت ۶۲تا ۶۹) وَ فِرْعَوْنَ ذِي الْاَوْتَادِ۪ۙ۰۰۱۱ اور فرعون (کے متعلق بھی تجھے کچھ معلوم ہے) جو پہاڑوں کا مالک تھا.الَّذِيْنَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ۪ۙ۰۰۱۲ (کیا تجھے) ان سب لوگوں کا (حال معلوم ہے) جنہوں نے شہروں میں سرکشی کر رکھی تھی حل لغات.اَوْتَادٌ.اَوْتَادٌ وَتَدٌ کی جمع ہے اور وَتَدٌ اس کھونٹے یا لکڑی کے اس کیلے کو کہتے جو دیوار یا زمین میں گاڑا جاتا ہے اَوْتَادُ الْاَرْضِ پہاڑوں کو کہتے ہیں.اَوْتَادُ الْبِلَادِکے معنے رؤسا کے ہوتے ہیں اَوْتَادُ الْفَمِ دانتوں کو کہا جاتا ہے (اقرب) اس لحاظ سے آیت کے کئی معنے ہو جائیں گے یہ بھی کہ وہ فرعون جو خیموں والا تھا.یا یہ کہ وہ فرعون جو پہاڑوں والا تھا یا بڑی بڑی عمارتوں والا تھا (بلند وبالا اور اونچی عمارت پر بھی وَتَد کا لفظ استعمال کر لیا جاتا ہے کیونکہ اس کی بنیاد زمین میں نہایت گہری کھودی جاتی ہے) طَغَوْا.طَغَوْا: طَغٰی سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے.اور طَغٰی کے معنے ہوتے ہیں اَسْـرَفَ فِی الْمَعَاصِیْ والظُّلْمِ.کہ ظلم اور گناہوں میں حد سے بڑھ گیا (اقرب) پس طَغَوْا کے معنے ہوئے وہ ظلم اور گناہوں میں حد سے بڑھ گئے.تفسیر.ذِی الْاَوْتَادِ کے تین معنے اس آیت میں فرعون اور اس کی قوم کے تمدن کا نقشہ کھینچا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ اس قوم کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ وہ بڑی بڑی اونچی عمارتیں بنایا کرتی تھی.یہ لازمی بات ہے کہ جو بھی اونچی عمارت بنائی جائے گی اس کی بنیاد باقی عمارات کی نسبت زیادہ گہری رکھنی پڑے گی چنانچہ
Page 245
قدیم مصری عمارتیں بہت بلند ہیں اہرام مصر اپنی بلندی اور شان، دنیا میں اپنی نظیر آپ ہیں.دوسرے معنے اس کے یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ خیموں والا تھا.مراد یہ ہے کہ وہ ایک متمدن ملک کا بادشاہ تھا اس میں آمدورفت کے لئے بڑی بڑی سڑکیں تھیں اور کشتیوں کے ذریعہ دور دور سفر ہو سکتا تھا اس وجہ سے بادشاہ ہمیشہ ملک میں دَورہ کرتا رہتا تھا.اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ فرعون مصر کے وقت میں ملک بہت متمدّن ہو گیا تھا.وہاں ہر قسم کی سہولتیں لوگوں کو میسر تھیں اور ان کی طرز رہائش بادیہ نشین لوگوں کی طرح نہیں رہی تھی بلکہ وہ لوگ بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے سڑکیں تیار کرتے تھے اور بادشاہ دورہ کر کے ملک کے حالات دیکھتا رہتا تھا.جن ملکوں میں عمارتوں کا رواج نہ ہو.اگر ان کے بادشاہ کی نسبت کہا جائے کہ وہ ذِی الْاَوْتَادِ تھا تو اس کے معنے یہ ہوں گے کہ گو وہ بادیہ نشین تھا مگر بڑی طاقت والا تھا.لیکن جب کسی شہر ی قوم کے متعلق ہم یہ الفاظ استعمال کریں گے تو اس کے معنے یہ ہوں گے کہ وہ قوم متمدن تھی.آمدورفت کے لئے ملک میں بڑی بڑی سڑکیں تھیں.اسی طرح دریا کے راستے کھلے تھے اور بادشاہ اور مختلف حکام کشتیوں کے ذریعہ دَورے کرتے رہتے تھے.پھر اَوْتَاد کے معنے رؤسا کے بھی ہوتے ہیں.اس لحاظ سے آیت کے یہ معنے ہوں گے کہ وہ صرف بادشاہ ہی نہیں تھا بلکہ شہنشاہ تھا.بڑے بڑے بادشاہ اور نواب اس کے ماتحت تھے اور وہ اپنی اپنی جگہ بادشاہ سمجھے جاتے تھے او ر لوگوں پر ان کو حکومت حاصل تھی.ذِی الْاَوْتَادِ کے ایک معنے جبلی حکومت کے بھی ہیں اور فِرْعَوْنَ ذِی الْاَوْتَادِ کہہ کر بتایا گیا ہے کہ اَوْتَادُ الْاَرْضِ یعنی جبال بھی اس کے ماتحت تھے یعنی اس کے زمانہ میں مصر کا پھیلاؤ بہت زیادہ تھا.یہاں تک کہ خرطوم وغیرہ کے علاقے یا ایبے سینیا کے کچھ علاقے جو اب مصر سے باہر ہیں وہ بھی اس کے ماتحت ہوتے تھے.چنانچہ پرانے آثار اب اس کی تصدیق کر رہے ہیں کہ مصری حکومت کا دائرہ بہت وسیع تھا اور بعض پہاڑی علاقے بھی اس کے اندر شامل تھے.فَاَكْثَرُوْا فِيْهَا الْفَسَادَ۪ۙ۰۰۱۳ جس کے نتیجہ میں انہوں نے ان (شہروں) میں بے حد فساد پیدا کر دیا تھا.تفسیر.یوں تو ہر برائی قابلِ نفرت ہے مگر د۲و وجوہ سے برائیاں نہایت بھیانک شکل اختیار کر لیتی ہیں
Page 246
ایک اپنی کثرت کی وجہ سے.دوسرے بڑے بڑے جرائم پر مشتمل ہونے کی وجہ سے.جب کسی قوم میں کثرت سے جرائم پائے جائیں اور پھر وہ جرائم ایسے ہوں جو نہایت سنگین ہوں اور بڑی بڑی خطرناک برائیوں پر مشتمل ہوں تو اس قوم کی تباہی اور بربادی کی ساعت تو بالکل ہی قریب آ جاتی ہے.اَکْـثَـرُوْا فِیْھَا الْفَسَادَ کی آیت کو صرف فرعون اور اس کی قوم پر بھی چسپاں کیا جا سکتا ہے اور عاد اور ثمود اور فرعون تینوں پر بھی اس کو چسپاں کیا جا سکتا ہے.زیادہ مناسب یہی ہے کہ اَکْـثَـرُوْا فِیْھَا الْفَسَادَ کو تینوں قوموں کے ساتھ لگایا جائے گو صرف فرعون اور اس کی قوم کے ساتھ بھی لگ سکتا ہے.فساد بڑے جرائم کے لئے بولا جاتا ہے اور اَکْـثَـرُوْا فِیْھَا الْفَسَادَ کہہ کر اس آیت میں بتایا ہے کہ ان لوگوں نے بڑے بڑے جرم بھی کئے اور پھر کثرت سے کئے.مثلاً ان اقوام میں شرک کی خطرناک وبا تھی اور پھر کثرت سے شرک پھیلا ہوا تھا اور اگر شرک کے علاوہ اور جرائم بھی لئے جائیں تو معنے یہ ہوں گے کہ وہ شرک بھی کرتے تھے اور دوسری خرابیاں بھی ان میںپائی جاتی تھیں.مثلاً ظلم کر لینا یا دوسروں کا حق مار لینا.بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہوں نے فساد کو انتہا تک پہنچا دیا تھا.عاد و ثمود کی تباہی کے ساتھ فرعون کی تباہی کا ذکر کرنے میں حکمت یہاں تین قوموں کو مثال کے طور پر بیان کیا گیا ہے عا۱د، ثمو۲د اور فرعو۳ن کی قوم کو.عاد اور ثمود یہ دونوں قومیں عرب کی تھیں اور فرعون کی قوم مصر سے تعلق رکھتی تھی.یہ تین مثالیں اللہ تعالیٰ نے بلاوجہ بیان نہیں کیں بلکہ اس لئے بیان کی ہیں کہ یہاں دو زمانوں کی خبر دی گئی تھی.ایک اس زمانہ کی جس میں مکہ والوں کے مظالم کی وجہ سے مسلمانوں پر دس۱۰ تاریک راتیں آنے والی تھیں اور ایک زمانہ مسیح موعودؑ کی.پہلی لیالی کا موجب چونکہ عرب لوگ تھے اور عاد اور ثمود ان کے وطن کے لوگ تھے اس لئے اللہ تعالیٰ ان کی مثال ان کے سامنے پیش کرتا ہے اور فرماتا ہے تمہارے ملک میں دو بڑی بڑی حکومتیں گذر چکی ہیں ایک تمہارے جنوب میں تھی اور دوسری تمہارے شمال میں تھی.ان دونوں کے حالات پر غور کرو اور سوچو کہ جب ان لوگوں نے انبیاء کا مقابلہ کیا اور فسادات کو انتہا تک پہنچا دیا تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کا نام و نشان تک مٹا دیا.باجود اس کے کہ یہ قومیں بڑی طاقت رکھتی تھیں پھر بھی جب انبیاء کے مقابلہ میں کھڑی ہوئیں خدا تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیااور ان کی طاقت ان کے کچھ بھی کام نہ آئی.تمہاری تو ان کے مقابلہ میں کوئی نسبت ہی نہیں پھر کیوں تم ان کے حالات سے عبرت نہیں پکڑتے اور کیوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کررہے ہو.اگر تم نے یہی طریق جاری رکھا تو جو سلوک ہم نے عاد اور ثمود سے کیا تھا وہی تمہارے ساتھ کریں گے.تم مت سمجھو کہ
Page 247
ان مظالم کے نتیجہ میں تم کامیاب ہو جاؤ گے جس طرح آج مسلمانوں پر تم مختلف قسم کے مظالم ڈھا رہے ہو اور تم نے ان کے دنوں کو بھی رات بنا دیا ہے.اسی طرح عاد اور ثمود نے بھی بڑی بڑی شرارتیں کی تھیں اور پھر حد سے زیادہ شرارتیں کی تھیں مگر پھر بھی وہ ناکام رہے حدیثوں سے پتہ لگتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا جرم کسی نبی کو قتل کرنا ہے ان لوگوں نے بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کیا جیسا کہ فرماتا ہے وَاِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِيُثْبِتُوْكَ اَوْ يَقْتُلُوْكَ اَوْ يُخْرِجُوْكَ١ؕ وَ يَمْكُرُوْنَ وَ يَمْكُرُ اللّٰهُ١ؕ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ (الانفال:۳۱) پھر مکہ والے شرک میں بھی مبتلا تھے اور شرک وہ گناہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ظلم عظیم قرار دیا ہے جیسا کہ فرماتا ہے اِنَّ الشِّرْکَ لَظُلْمٌ عَظِیْمٌ (لقمان:۱۴) پھر اَکْـثَـرُوْا فِیْھَا الْفَسَادَ کے دوسرے معنوں کے مطابق کفار مکہ نے نہ صرف بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کیا بلکہ مظالم کو انتہاء تک پہنچا دیا.جو شخص بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم پر ایمان لایا انہوں نے اس کو دکھ دینا شروع کر دیا بلکہ وہ تلاش کر کر کے مسلمانوں کو پکڑتے اور ان کو بڑی بے دردی سے مارتے پیٹتے اور مختلف رنگوں میں عذاب دیتے یہاں تک کہ کئی مسلمان بھاگ کر ایبے سینیا چلے گئے مگر ان کا جوش پھر بھی نہ تھما اور وہ حبشہ تک محض اس لئے گئے کہ مسلمانوں کو پکڑ کر واپس لائیں.اور ان کو اپنے مظالم کا تختۂ مشق بنائے رکھیں(السیرۃالنبویۃ لابن ھشام زیر عنوان ارسال قریش الی الحبشۃ فی طلب المھاجرین الیھا).اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے مکہ والو! پہلی قومیں بھی تمہارے ملک میں ایسی گذر چکی ہیں جنہوں نے فسادات کو انتہا تک پہنچا دیا تھا.تم یہ نہ سمجھو کہ تمہاری یہ سرکشی اور ظلم تمہارے حق میں مفید ہو گا.وہ قومیں بھی اسی خیال میں مبتلا رہی تھیں کہ ہم خوب ظلم ڈھا رہی ہیں مگر آخر ایک دن آیا کہ وہ تباہ وبرباد کر دی گئیں.اسی طرح تم ایک دن خدا تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بن جاؤ گے اور عاد اور ثمود کی طرح دنیا سے مٹ جاؤ گے.فرعون کی تباہی کے ذکر میں مسیح موعودؑ کے زمانہ میں اس جیسا واقعہ ہونے کی پیشگوئی اس کے بعد فرعون کا ذکر کیا.میرے نزدیک اس میں مسیح موعودؑ کے زمانہ کی خبر ہے.میں ابھی تک تفصیل سے نہیں بتا سکتا کہ کیوں؟ مگر دو باتیں میں بیان کر دیتا ہوں جن کی بنا پر کہا جا سکتا ہے کہ اس مثال کا مسیح موعودؑ کے زمانہ کے ساتھ تعلق ہے اور وہ دو باتیں یہ ہیں.کہ اوّل رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم فرماتے ہیں کہ محرم کی دسویں رات ایک خاص شان اور عظمت رکھتی ہے کیونکہ اس دن میں خدا تعالیٰ نے موسٰی کو فرعون سے نجات دی اور میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی ایسا ہی معاملہ میری امت میں ایک دفعہ ہوگا اور میری امت کو اس دن ایک عذاب سے نجات ملے گی.گو بظاہر یہاں فرعون اور اس کے مظالم سے نجات کے الفاظ ہیں مگر ان میں یہ اشارہ پایا جاتا
Page 248
ہے کہ اس رنگ کا کوئی واقعہ آئندہ ہونے والا ہے.دوسری دلیل یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃوالسلام فرماتے ہیں.’’دیکھا کہ میں مصر کے دریائے نیل پر کھڑا ہوں اور میرے ساتھ بہت سے بنی اسرائیل ہیں اور میں اپنے آپ کو موسٰی سمجھتا ہوں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم بھاگے چلے آتے ہیں نظر اٹھا کر پیچھے دیکھا تو معلوم ہوا کہ فرعون ایک لشکر کثیر کے ساتھ ہمارے تعاقب میں ہے اور اس کے ساتھ بہت سامان مثل گھوڑے، گاڑیوں، رتھوں وغیرہ کے ہے اور وہ ہمارے بہت قریب آ گیا ہے.میرے ساتھی بنی اسرائیل بہت گھبرائے ہوئے ہیں اور اکثر ان میں سے بے دل ہو گئے ہیں اور بلند آواز سے چلاتے ہیں کہ اے موسٰی ہم پکڑے گئے تو میں نے بلند آواز سے کہا کَلَّا اِنَّ مَعِیَ رَبِّیْ سَیَھْدِیْنِ اتنے میں مَیں بیدار ہو گیا اور زبان پر یہی الفاظ جاری تھے (تذکرہ صفحہ۴۲۹) اسی طرح آپ کا ایک یہ بھی الہام ہے.یَاْتِیْ عَلَیْکَ زَمَنٌ کَمِثْلِ زَمَنِ مُوْسٰی (تذکرہ صفحہ ۴۲۳) کہ تجھ پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے جو موسٰی کے زمانہ کی طرح ہو گا.پس جبکہ حدیث میں یہ اشارہ ہے کہ موسٰی کی طرح کا ایک واقعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم کی امت میں ہونے والا ہے اور تاریخ شاہد ہے کہ اب تک کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا.دوسری طرف خدا تعالیٰ کا وہ مامور جو موجودہ زمانہ میں آیا، اسے بتایا گیا کہ وہ موسٰی ہے، فرعون اس کا پیچھا کرے گا اس کے ساتھی گھبرا جائیں گے اور کہیں گے کہ اے موسٰی ہم پکڑے گئے اس وقت موسٰی بلند آواز سے کہے گا کہ کَلَّا اِنَّ مَعِیَ رَبِّیْ سَیَھْدِیْنِ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا خدا میرے ساتھ ہے.ان دو۲ الہامات کے ساتھ اگر میرے اس رؤیا کو بھی ملا لیا جائے جو الفضل میں شائع ہو چکا ہے کہ میں ایک مکان میںٹھہرا ہوا ہوں.’’اس وقت میرے دل میں خیال آتا ہے کہ جس مکان میں مَیں ٹھہرا ہوا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اسی میں پناہ لی تھی.‘‘ (الفضل جلد ۳۲ نمبر ۱۴۲ مورخہ ۲۰؍جون۱۹۴۴ء صفحہ ۱ ) تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ آئندہ کے متعلق ایک پیشگوئی ہے جو لَیَالِی عَشْـر کے دوسرے ظہور میں گیارھویں رات یعنی انیسویں صدی میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ذریعہ پوری ہو گی اور موسٰی کی مصر سے نجات کی قسم کا کوئی واقعہ جماعتِ احمدیہ کو پیش آئے گا.
Page 249
پس چونکہ یہاں مسیح موعود کا بھی ذکر تھا اس لئے جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم کے دشمنوں کے لئے عاد اور ثمود کی مثال دی وہاں مسیح موعود کے دشمنوں کے لئے فرعون کا واقعہ بطور مثال پیش کیا گیا.فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍۚۙ۰۰۱۴ اس پر تیرے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا.حلّ لُغات.صَبَّ.صَبَّ: صَبَّ الْمَاءَ کے معنے ہوتے ہیں.اس نے پانی کو بہا دیا.صَبَّ لازم بھی ہے اور متعدی بھی یعنی صَبَّ کے معنے بہانے کے بھی ہیں اور بہنے کے بھی ہیں.(اقرب) سَوْطٌ سَوْطٌ: کوڑے کوبھی کہتے ہیں اور سَوْطٌ کے معنے حصہ کے بھی ہوتے ہیں اور سَوْطٌ کے معنے سختی کے بھی ہوتے ہیں.اسی طرح سَوْطٌ جوہڑ کو بھی کہتے ہیں یعنی اس نشیب دار زمین کو بھی سَوْطٌ کہا جا تا ہے جہاں پانی جمع ہو جاتا ہے (اقرب) تفسیر.فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ کے تین معنے اگر سَوْطٌ کے معنے کوڑے کے لئے جائیں تو فَصَبَّ عَلَیْھِمْ رَبُّکَ سَوْطَ عَذَابٍ کے یہ معنے ہوں گے کہ خدا تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب کے کوڑے برسا دیئے.ہمارے ملک میں بھی کوڑوں کے متعلق برسانے کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہی محاورہ یہاں استعمال کیا گیا ہے کہ ان پر تیرے رب نے عذاب کے کوڑے برسانے شروع کر دیئے جس طرح قطرہ کے بعد قطرہ گرتا ہے اسی طرح ان پر عذاب کے بعد عذاب نازل ہو گا.اور انہیں ہوش ہی نہیں آئے گا.یہاں تک کہ وہ تباہ ہو جائیں گے.اگر سَوْط کے معنے حصہ کے کئے جائیں تو اس آیت کے یہ معنے ہوں گے کہ اس قوم کا عذاب الٰہی میں جو حصہ مقدر تھا اس کے متعلق اسے کہا جائے گا کہ لو اپنا سارا حصہ عذاب کا لے لو.تم نے ہمارے نبیوں کو دکھ دیا تھا انہوں نے اپنا حصہ دکھوں میں سے لے لیا اور تم اپنا حصہ لو.اگر سَوْط کے معنے جوہڑ کے کئے جائیں تو آیت کا مفہوم یہ ہو گا کہ عذاب کا جوہڑ سارے کا سارا ان پر الٹا دیا جائے گا.چونکہ سَوْط اس نشیب دار زمین کو کہتے ہیں جس میں پانی جمع ہو جاتا ہے اس لئے سَوْط کہہ کر اس طرف بھی اشارہ کیا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے عذاب کے احکام نازل ہو کر ان کا ذخیرہ جمع ہوتا رہتا ہے.ان کی ہر شرارت
Page 250
پر عذاب نازل نہیں ہوگا بلکہ وہ عذاب جمع ہوتا رہے گا یہاں تک کہ ایک دن سارے کا سارا جوہڑ ان پر الٹا دیا جائے گا.اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ۠ؕ۰۰۱۵ تیرا رب یقیناً گھات میں (لگا ہوا) ہے.تفسیر.فرماتا ہے تیرا رب مجرموںکی گھات میں رہتا ہے جب وہ ان کو پکڑتا ہے تو اکٹھا پکڑتا ہے.کہتے ہیں سو سنار کی اور ایک لوہار کی.اسی طرح خدا تعالیٰ کا قاعدہ ہے کہ وہ ڈھیل دیتا چلا جاتا ہے اور مجرم انسان سمجھتا ہے کہ مجھے میرے برے کاموں کی کوئی سزا نہ ملے گی.مگر آخر ایک دن ایسا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی گرفت میں لے لیتا اور اسے تباہ اور برباد کر دیتا ہے.یہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم کے دشمنوں کے ساتھ سلوک ہوگا.ہم ان کو ڈھیل دیں گے اور گیا۱۱رہ سال تک دیتے چلے جائیں گے مگر آخر ایک دن آئے گا جب قیدار کی ساری حشمت کو خاک میں ملا دیا جائے گا.اور مومنوں کے دکھ کو خوشی میں بدل دیا جائے گا.اسی طرح اس پیشگوئی کے دوسرے ظہور کے وقت انیسو۱۹یں٭ صدی میں کوئی فرعون اتنا خطرناک ظلم کرے گا کہ جماعت پکار اٹھے گی.یٰمُوْسٰۤى اِنَّا لَمُدْرَكُوْنَ اے موسیٰ اب تو ہماری تباہی سر پر آ پہنچی.اب ہم کسی طرح اس فرعون کے پنجۂ ظلم سے بچ نہیں سکتے اس وقت جماعت کا جو بھی لیڈر ہو گا وہ موسٰی کی طرح اپنے ساتھیوں سے کہے گا کَلَّا یہ بالکل غلط بات ہے کہ دشمن تمہیں تباہ اور برباد کر دے گا.اِنَّ مَعِیَ رَبِّیْ سَیَھْدِیْنِ.میرے ساتھ میرا رب ہے اور وہ مجھے ہدایت دے دے گا.میں نے وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ کی تشریح کر تے ہوئے بیان کیا تھا کہ جب کفار غار ثور کے منہ پر پہنچ گئے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو گھبراہٹ طاری ہوئی تو اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم نے ان الفاظ میں ان کو تسلی دی کہ لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰہَ مَعَنَا(التوبۃ:۴۰) یعنی غم مت کر ایک وتر بھی ہمارے ساتھ ہے.اسی طرح جب جماعت احمدیہ کسی فرعون کے مظالم کی وجہ سے سخت گھبرا اٹھے گی اس وقت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام جماعت احمدیہ کو روحانی طور پر اس کے خلیفہ اور امام کی زبان سے کیونکہ وہ دو۲ نہیں بلکہ ایک ہی وجود ہوں گے.٭غلطی سے انیسویں صدی لکھا گیا ہے، مراد بیسویں صدی ہے جو ۱۹۰۱ء سے شروع ہو کر ۲۰۰۰ء تک ہے.(ناشر)
Page 251
جب کہ وہ غم وہم کے تمثیلی سمندر کے کنارے پر کھڑا ہو گا.یاممکن ہے کہ مصر یا اور کسی ملک میں ایسے ہی حالات پیدا ہونے پر.اور واقعہ میں دریائے نیل کے کنارے پر یا اور کسی دریا کے کنارے پر بڑے جاہ وجلال کے ساتھ فرمائیں گے کَلَّا اِنَّ مَعِیَ رَبِّیْ سَیَھْدِیْنِ.کَلَّا کے معنے یہی ہیں لَاتَحْزَنْ غم مت کرو اِنَّ مَعِیَ رَبِّیْ سَیَھْدِیْنِ میرے ساتھ میرا رب ہے یعنی ایک وتر بھی ہمارے ساتھ ہے اور وہ اس لَیْل میں سے ہمیں نکال کر لے جائے گا.فَاَمَّا الْاِنْسَانُ اِذَا مَا ابْتَلٰىهُ رَبُّهٗ فَاَكْرَمَهٗ پس (ذرا دیکھو تو )انسان کی حالت (کو جو) یہ ہے کہ جب اس کا رب اسے آزمائش میں ڈالتا ہے.اور اس کی عزت کرتا ہے وَ نَعَّمَهٗ١ۙ۬ فَيَقُوْلُ رَبِّيْۤ اَكْرَمَنِؕ۰۰۱۶وَ اَمَّاۤ اِذَا مَا ابْتَلٰىهُ اور اس پر نعمت کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ (دیکھو میں ایسا ذی شان ہوں کہ) میرے رب نے (بھی) میری عزت کی.اور جب فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهٗ١ۙ۬ فَيَقُوْلُ رَبِّيْۤ اَهَانَنِۚ۰۰۱۷ اسے آزمائش میں ڈالتا ہے.اور اس کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے میری (بلا وجہ) بے عزتی کی.حلّ لُغات.اِبْتَلَاہُ.اِبْتَلَاہُ: کے معنے ہوتے ہیں اِخْتَبَـرَہٗ.اس کی حقیقت کو ظاہر کیا اور اِبْتَلَی الْاَمْرَ کے معنے ہوتے ہیں عَرَفَہٗ.اس کو جان لیا.اصل میں یہ لفظ بَلِیَ یَبْلٰی ہے اور بَلَاہُ یَبْلُوْہُ (بَلْوًا) بھی استعمال کیا جاتا ہے بَلِیَ الثَّوْبُ کے معنے ہوتے ہیں خَلَقَ کپڑا پرانا ہو گیا اور گھس گیا اور بَلَاہُ (یَبْلُوْہُ بَلْوًا) کے معنے ہیں جَرَّبَہٗ وَاخْتَبَرَہُ.اس کا تجربہ کیا.اس کی حقیقت کو ظاہر کیا اور اس کے اندرونہ کو معلوم کیا.(اقرب) مفردات والے لکھتے ہیں کہ بَلَوْتُہٗ کے معنے اِخْتَبَرْتُہٗ کے اس لئے ہیں کہ خواہ یہ لفظ بَلِیَ یَبْلٰی سے ہو یا بَلَاہُ یَبْلُوْہُ بَلْوًا سے دونوں صورتوں میں اس میںپرانے ہونے کی حقیقت پائی جاتی ہے.وہ کہتے ہیں بَلَوْتُہٗ: اِخْتَبَرْتُہٗ کَاَنِّیْ اَخْلَقْتُہٗ مِنْ کَثْرَۃِ اِخْتِبَارِیْ لَہٗ یعنی بَلَوْتُہٗ کے معنے اِخْتَبَرْتُہٗ ا س لئے کئے جاتے ہیں کہ اس میں یہ مفہوم پایا جاتا ہے کہ میں نے اسے بار بار دیکھ کر پرانا کر دیا ہے.اسی لئے ابتلا کا لفظ ایسے امر کے متعلق استعمال کیا جاتا ہے جس کی انسان پوری طرح تحقیق کرلے.جیسے انسان کپڑا خرید کر لاتا ہے تو عورتیں اس کپڑے کو ہاتھوں سے گھستی ہیں یہ دیکھنے کے لئے کہ اس کی مایا کیسی ہے یا اس کا رنگ اترے گا کہ نہیں یہ بار بار دیکھنا اس لئے
Page 252
ہوتا ہے تاکہ رائے پختہ ہو جائے.اس بار بار کے فعل سے چونکہ چیز پرانی ہوتی ہے اس لئے بَلِیَ کا لفظ اسی حقیقت کے اشتمال کی وجہ سے بولا جاتا ہے (پنجابی میں بھی محاورہ ہے کہ یہ چیز تو میری ہنڈائی ہوئی ہے یعنی کثرت سے اس کے ساتھ میرا معاملہ پڑا ہے اور میں اس کی حقیقت سے واقف ہوں) اسی طرح تَبْلُوْا کُلُّ نَفْسٍ مَااَسْلَفَتْ کے معنے ہیں تَعْرِفُ حَقِیْقَۃَ مَا عَـمِلَتْ یعنی ہر شخص اپنے عمل کی حقیقت کو جان لے گا.وَسُـمِّیَ الْغَمُّ بَلَاءً مِنْ حَیْثُ اَنَّہٗ یُبْلِی الْـجِسْمَ.غم کو بھی اسی لئے بَلَاء کہتے ہیں کہ وہ جسم کو دُبلا کر دیتا ہے اور اس کی طاقت کو کمزور کر دیتا ہے اسی طرح صاحب مفردات لکھتے ہیں کہ سُـمِّیَ التَّکْلِیفُ بَلَاءً مِّنْ اَوْجُہٍ تکلیف کو بھی عربی زبان میں بَلَاء کہتے ہیں اور اس کی کئی وجوہ ہیں اَحَدُھَا اَنَّ التَّکَالِیْفَ کُلَّھَا مَشَاقٌّ عَلَی الْاَبْدَانِ.پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جب تکلیفیں آتی ہیں انسان پر ایک بوجھل کام آ پڑتا ہے اور ان تکالیف کا اس کے جسم پر اثر پڑتا ہے اس لئے اس کو بلا کہتے ہیں وَالثَّانِیْ اَنَّـھَا اِخْتِبَارَاتٌ(مفردات) دوسرے اس لئے کہ جب انسا ن پر بوجھ پڑتا ہے تبھی اس کی حقیقت ظاہر ہوتی ہے.وہ شخص جسے کسی بڑی جنگ میں شامل ہونے کا موقع نہیں ملا اس کی بہادری کا کس طرح پتہ چل سکتا ہے یا جسے متواتر بوجھ اٹھانے کا موقع نہیں ملا اس کا استقلال کس طرح نظر آ سکتا ہے.یوں تو ہر شخص اپنے متعلق سمجھ لیتا ہے کہ میں بڑا واقف اور ماہر ہوں.لیکن اس کی واقفیت یا مہارت تب معلوم ہوتی ہے جب اس پر کوئی بڑا بوجھ آ کر پڑتا ہے اسی لئے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَ لَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتّٰى نَعْلَمَ الْمُجٰهِدِيْنَ مِنْكُمْ وَ الصّٰبِرِيْنَ( محمد:۳۲) یعنی ہم تمہیں تکلیفوں میں ڈالیں گے یہاں تک کہ تم میں سے مجاہدوں اور صابروں کو ممتاز کر کے دکھا دیں.وَالثَّالِثُ اَنَّ اخْتِبَارَ اللہِ تَعَالٰی لِلْعِبَادِ تَارَۃً بِالمَسَارِّ لِیَشْکُرُوْا وَتَارَۃً بِالْمَضَارِّ لِیَصْبِرُوْا.تیسری وجہ مفردات کے مصنف یہ بتاتے ہیںکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے بندے کی حقیقت کو اس طرح ظاہر کیا جاتا ہے کہ کبھی اس کو خوشیاں پہنچائی جاتی ہیں تا کہ یہ دیکھا جائے کہ اس میں شکر کا مادہ ہے یا نہیں اور کبھی اس کو تکالیف میں ڈالا جاتا ہے تاکہ یہ دیکھا جائے کہ اس میں صبر کا مادہ ہے یا نہیں فَصَارَتِ الْمِحْنَۃُ وَالْمِنْحَۃُ جَـمِیْعًا بَلَاءً فَالْمِحْنَۃُ مُقْتَضِیَۃٌ لِلصَّبْرِ وَالْمِنْحَۃُ مُقْتَضِیَۃٌ لِلشُّکْرِ.پس ابتلا اور تکالیف صبر ظاہر کرنے کا موجب بن جاتی ہیں اور انعامات اس کے جذبۂ شکر کو ظاہر کرنے کا موجب بن جاتے ہیں.جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی انعام نازل ہوتا ہے اس وقت انعام کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ انسان شکر کرے اور جب اسے کوئی ٹھوکر لگے تو اس وقت مصیبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ انسان صبر کرے وَالْقِیَامُ بِـحُقُوْقِ الصَّبْرِ اَیْسَـرُ مِنْ الْقِیَامِ بِـحُقُوْقِ الشُّکْرِ (مفردات) پھر وہ کہتے ہیں کہ جب خدا تعالیٰ کی طرف سے امتحان بذریعہ صبر لیا جاتا ہے
Page 253
اور انسان پر مختلف تکالیف اور مصیبتیں آتی ہیں تو یہ زیادہ آسان ہوتا ہے.مصیبتیں آتی ہیں تو وہ سمجھتا ہے اب تو یہ سر پر آ ہی پڑی ہیں ان کو برداشت کرنا چاہیے اور کہتا ہے کہ جو مصیبت پڑگئی سو پڑ گئی اور اس وجہ سے وہ صبر سے کام لے لیتا ہے.لیکن جو شکر کے ذریعہ ابتلا آتا ہے وہ نہایت خطرناک ہوتا ہے کیونکہ انسان کہتا ہے جو چیز میرے قبضہ میں آ گئی ہے اس سے میں پوری طرح حظّ اٹھا لوں اس طرح وہ خدا کو بھول جاتا ہے.صبر کے ساتھ ماضی کا تعلق ہے اور ماضی کو انسان بھلا سکتا ہے لیکن انعام کا مستقبل کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اور مستقبل کو بھلانا بڑ ا مشکل ہوتا ہے اسی لئے وہ کہتے ہیں کہ اصل ابتلا وہ ہے جو انعام کے رنگ میں آتا ہے.مثلاً اللہ تعالیٰ کسی کو دولت دیتا ہے، کسی کو صحت دیتا ہے، کسی کو عزت دیتا ہے، کسی کو طاقت دیتا ہے، کسی کو حکومت دیتا ہے.یہ مختلف انعامات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کئے جاتے ہیں لیکن بسا اوقات انسان دولت اور عزت کے ملنے پر خدا تعالیٰ کو بالکل بھول جاتا ہے.طاقت کے ملنے پر تکبّر میں مبتلا ہوجاتا ہے.تجارت اور صنعت و حرفت یا زمیندارہ کے کام میں ترقی حاصل ہونے پر اپنے اموال کا غلط استعمال کرتا ہے، مقدمات میں روپیہ برباد کرتا ہے، غریبوں کی حق تلفی کرتا ہے، اسی طرح اپنے ہاتھوں اپنی آنکھوں اور اپنے کانوں وغیرہ کا ناجائز استعمال کرتا ہے پس اس ابتلا میں کامیاب اترنا زیادہ مشکل ہوتا ہے بہ نسبت اس کے کہ کوئی شخص مر جائے تو دوسرا سن کر کہہ دے.اِنَّا لِلّٰهِ وَ اِنَّاۤ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ.جب کسی شخص کو خدا تعالیٰ کی طرف سے دولت ملتی ہے تو اس کا اپنے نفس کو عیاشی سے روکنا، اچھے کھانے اور اچھے پہننے سے روکنا بڑا مشکل ہوتا ہے.اسی لئے وہ کہتے ہیں کہ ابتلا انعامی زیادہ مشکل ہوتے ہیں اور ان میں بہت کم لوگ کامیاب ہوا کرتے ہیں.حضرت عمرؓ کا ایک قول بھی انہی معنوں میں پایا جاتا ہے وہ فرماتے ہیں بُلِیْنَا بِالضَّـرَّاءِ فَصَبَرْنَا کہ ہماری اُمت پر اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی مصیبتیں ڈالیں لیکن ہم نے صبر سے کام لیا اور کوئی شخص ہم میں سے ان مصیبتوں پر نہیں گھبرایا وَبُلِیْنَا بِالسَّـرَّاءِ فَلَمْ نَصْبِرْ (مفردات ) لیکن پھر ہم پر خدا تعالیٰ نے انعامات والے ابتلا وارد کئے.جب انعامی ابتلا اللہ تعالیٰ نے ہم پر ڈالا تو کئی لوگ ہم میں سے صبر نہ کر سکے چنانچہ دیکھ لو صحابہؓ کی تکلیفوں کے زمانہ میں ان میں سے ایک شخص بھی اپنے مذہب سے منحرف نہیں ہوا.لیکن انعام کے زمانہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم کی وفات کے معاً بعد بادشاہت اور خلافت کے جھگڑے میں سارا عرب مرتد ہو گیا سوائے مکہ اور مدینہ کے ان لوگوں کے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم کی صحبت میں رہے تھے گو وہ مرتد ہونے والے صحابی نہ تھے لیکن بہرحال وہ قریب کے مسلمان تھے اور انہوں نے خدا تعالیٰ کی تائیدات اور اس کی نصرتوں کے نشانات دیکھے ہوئے تھے.لیکن باوجود اس کے کہ انہوں نے تازہ بتازہ
Page 254
نشانات دیکھے تھے سب کے سب مرتد ہو گئے.حدیثوں میں آتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صرف مکہ اور مدینہ میں ہی باجماعت نماز ہوا کرتی تھی باقی ہر جگہ ارتداد کی وبا پھیلی ہوئی تھی (البدایۃ والنـھایۃ جزء سادس صفحہ ۳۴۴) سو حضرت عمرؓ فرماتے ہیں بُلِیْنَا بِالضَّـرَّاءِ فَصَبَـرْنَا.ہم پر مصائب آئے.بڑی بڑی مشکلات آئیں مگر ہم نے جرأت دکھلائی، ہمت کا مظاہرہ کیا اور ان مصائب سے ذرا بھی نہ گھبرائے وَبُلِیْنَا بِالسَّـرَّاءِ فَلَمْ نَصْبِرْ لیکن جب خدا تعالیٰ نے انعام پر انعام.فتح پر فتح.نصرت پر نصرت اور دولت پر دولت دی تو ہماری جماعت سو فی صدی اس امتحان میں پاس نہ ہو سکی جس طرح پہلے پاس ہوئی تھی وَلِھٰذَا قَالَ اَمِیْرُ الْمُؤْمِنِیْنَ.اسی بنا پر امیرالمومنین کہتے ہیں (یہ یاد رکھنا چاہیے کہ محاورہ میں امیر المومنین سے مراد صرف حضرت علیؓ ہوتے ہیں گو تمام خلفاء ہی امیرالمومنین ہیں لیکن بعض اسلامی مصنفین میں چونکہ تفضیلی رنگ پایا جاتا تھا اور وہ حضرت علیؓ کو اپنے درجہ میں باقی تمام خلفاء سے بڑا سمجھتے تھے اس لئے انہوں نے یہ محاورہ بنا دیا کہ جب وہ امیرالمومنین کا لفظ استعمال کرتے تو اس سے مراد محض حضرت علیؓ ہی ہوتے.اس جگہ بھی غالباً حضرت علیؓ ہی مراد ہیں.وہ فرماتے ہیں) مَنْ وُسِّعَ عَلَیْہِ دُنْیَاہُ فَلَمْ یَعْلَمْ اَنَّہٗ قَدْ مُکِرَ بِہٖ فَھُوَ مَـخْدُوْعٌ عَنْ عَقْلِہٖ یعنی جس کے لئے اس کی دنیا وسیع ہو جائے، اسے ہر قسم کی آسائشیں اور سامان میسر آ جائیں، اسے کثرت سے دولت مل جائے فَلَمْ یَعْلَمْ اَنَّہٗ قَدْ مُکِرَ بِہٖ اور اسے یہ پتہ نہ لگے کہ اسے ابتلا میں ڈالا جا رہا ہے گویا دولت بڑھنے اور آسائش کے سامانوں میںزیادتی ہونے سے اس کے دل میں یہ احساس پیدا نہ ہو کہ میرے لئے یہ آرام کی صورت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اس ذریعہ سے میرا امتحان لے رہا ہے تو فَھُوَ مَـخْدُوْعٌ عَنْ عَقْلِہٖ ایسا شخص یقیناً پاگل ہے درحقیقت صحیح الدماغ انسان وہی ہے کہ جب مصائب ومشکلات آئیں تب بھی وہ سمجھے کہ خدا تعالیٰ میرا امتحان لے رہا ہے اور اگر اسے انعامات ملیں یا دولت کی فراوانی اسے حاصل ہو جائے تب بھی وہ یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ میرا امتحان لے رہا ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَبْلُوْكُمْ بِالشَّرِّ وَ الْخَيْرِ فِتْنَةً(الانبیاء:۳۶) ہم تمہارے ایمان کو آزمانے کے لئے کبھی ترقی دیں گے اور کبھی دکھ دیں گے.گویا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو کچھ فرمایا وہ قرآن کریم سے ہی ماخوذ تھا.قرآن کریم میں یہی مضمون بیان کیا گیا ہے کہ ابتلا کے معنے عذاب کے ہی نہیں یعنی یہی نہیں کہ اگر کوئی موت واقع ہو جائے یا کوئی مالی نقصان پہنچ جائے تو یہ ابتلا ہے بلکہ کسی کو مال و دولت کا مل جانا بھی ایک ابتلا ہے.اور یہ بھی ویسا ہی خطرناک ہے جیسے ابتلاءِ تکلیف خطرناک ہے اور دولت و عزت کی فراوانی کا حاصل ہونا بھی ویسا ہی ڈر کا مقام ہے جیسے دولت و عزت کا چھینا جانا ڈر کا مقام ہے.اگر آج کسی شخص کی
Page 255
بھینس مر جائے، کل اس کے گھر میں چوری ہو جائے، پر سوں اس کا کتا مر جائے، اترسوں اس کا گھوڑا ہلاک ہوجائے، اگلے روز کسی عزیز کی موت ہو جائے تو اس وقت اس کے دل میں کتنی سخت گھبراہٹ پیدا ہو گی.کئی کم ایمان والے بھی یہ حالت دیکھ کر سمجھنے لگ جائیں گے کہ اب ہمیں خدا تعالیٰ کی طرف سے گناہوں کی سزا مل رہی ہے لیکن اگر آج کسی کو سو روپیہ مل جائے،دوسرے دن دو سو روپیہ مل جائے، تیسرے دن تین سو روپیہ مل جائے، چوتھے دن ایک مربع زمین مل جائے، پانچویں دن ایک گھوڑا انعام میں مل جائے، چھٹے دن گورنمنٹ کی طرف سے کوئی خطاب مل جائے تو اس کے دل کے کسی گوشہ میں بھی یہ خیال نہیں آئے گا کہ میں کہیں ہلاک نہ ہو جاؤں کہیں یہ چیزیں میری بربادی کا باعث نہ بن جائیں حالانکہ جس طرح مصائب کے ہجوم کے وقت اس کی ہلاکت اور گرنے کا امکان ہوتا ہے اسی طرح نعمتوں کے ملنے پر اس کی ہلاکت اور گرنے کا امکان ہوتا ہے.جس طرح وہ چیزیں خدا تعالیٰ کے عذاب کو قریب کر کے دکھانے لگ جاتی ہیں اسی طرح بسا اوقات یہ چیزیں انسان کو اس لئے ملتی ہیں کہ پتہ لگایا جاتا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ سے کیسا تعلق رکھتا ہے.درحقیقت دولت کمانا منع نہیں.بشرطیکہ وہ دین میں حارج نہ ہو.صرف دولت کے ساتھ محبت کرنا یا اس کا ناجائز استعمال منع ہے ورنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم کے صحابہؓ کے پاس ویسی ہی دولتیں تھیں جیسے آج کل بڑے بڑے امراء کے پاس ہوتی ہیں.حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کے متعلق تاریخوں میں آتا ہے کہ ان کی وفات کے بعد اڑھائی کروڑ روپیہ کے برابر ان کی جائیداد نکلی.اس وقت کا اڑھائی کروڑ روپیہ آج کل کے تیس چالیس کروڑ روپیہ کے برابر بن جاتا ہے.لیکن اس کے باوجود ان کا کھانا پینا ویسا ہی تھا جیسے عام مسلمانوں کا تھا وہ اپنی آمدنی کے متعلق کوشش کرتے تھے کہ اسے خدا تعالیٰ کے رستہ میں صرف کر دیں.ان کی اولاد نے آگے ایسا کیا یا نہیں یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے لیکن وہ اپنی زندگی میں بلادریغ خدا تعالیٰ کی راہ میں اپنا روپیہ خرچ کرتے رہتے تھے.تو کسی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر کا ملنا بھی ایک آزمائش ہوتی ہے.پھر صاحب مفردات لکھتے ہیں وَاِذَا قِیْلَ ابْتَلٰی فُلَانٌ کَذَا وَابْلَاہُ فَذَالِکَ یَتَضَمَّنُ اَمْرَیْنِ یعنی جب یہ کہا جائے کہ فلاں شخص نے فلاں کا اس اس رنگ میں امتحان لیا تو اس کے دو معنے ہو سکتے ہیں.اَحَدُھُمَا تَعَرُّفُ حَالِہٖ وَالْوُقُوْفُ عَلٰی مَا یُـجْھَلُ مِنْ اَمْرِہٖ.ایک تو یہ کہ اس کا اندرونہ معلوم کیا اور جو حقیقت پوشیدہ تھی وہ ظاہر کی.وَالثَّانِیْ ظُھُوْرُ جَوْدَتِہٖ وَ رَدَاءَتِہٖ دوسرے معنے یہ ہوتے ہیں کہ اس کے اندرونہ کو دنیا پر ظاہر کیا جائے خبث ہو تو اس کا خبث ظاہر ہو جائے اور اگر نیکی ہو تو نیکی ظاہر ہو جائے.گویا ایک تو جاننے کا یہ مفہوم ہوتا ہے کہ ہمیں خود کسی چیز کی حقیقت کا علم ہو جائے.مگر ایک معنے یہ ہوتے ہیں کہ کسی دبی ہوئی چیز کو ابھار دیا جائے اور اس کی جودت یعنی اس کی
Page 256
خوبی اور اس کے حسن کو یا اس چیز کی ردأت کو ظاہر کر دیا جائے وَرُبَّـمَا قُصِدَ بِہِ الْاَمْرَانِ.اور کبھی کبھی یہ دونوں باتیں مدنظر ہوتی ہیں.یعنی ابتلا کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس کے یہ معنے بھی ہوتے ہیں کہ مخفی حالت جاننا اور یہ بھی معنے ہوتے ہیں کہ مخفی حالات کو ظاہر کرنے کا موقع دینا وَرُبَّـمَا یُقْصَدُ بِہٖ اَحَدُھُمَا.اور کبھی صرف ایک ہی مراد ہوتی ہے یعنی کبھی صرف جاننا مراد ہوتا ہے اور کبھی صرف اس کا ظہور مراد ہوتا ہے فَاِذَا قِیْلَ فِی اللّٰہِ تَعَالٰی بَلٰی کَذَا اَوْاَبْلَاہُ فَلَیْسَ الْمُرَادُ مِنْہُ اِلَّا ظُہُوْرَ جَوْدَتِہٖ وَرَدَاءَتِہٖ.یعنی جب خدا تعالیٰ کے متعلق یہ لفظ بولا جائے اور کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ابتلا میں ڈالا تو اس کے معنے جاننے کے نہیں ہوتے بلکہ ہمیشہ اس کے معنے یہ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندرونہ کو ظاہر ہونے کا موقعہ دیا.اگر گند تھا تو اس گند کے ظاہر ہونے کا موقعہ پیدا کر دیا اور اگر اچھائی تھی تو اس کی خوبی کے ظاہر ہونے کا موقعہ پیدا کر دیا دُوْنَ التَّعَـرُّفِ لِـحَالِہٖ وَالْوُقُوْفِ عَلٰی مَا یُـجْھَلُ مِنْ اَمْرِہٖ.اس کے حال کو جاننے کے معنے نہیں ہوتے اور اس کے پوشیدہ امر پر واقف ہونے کے معنے بھی نہیں ہوتے اِذْکَانَ اللہُ عَلَّامَ الْغُیُوْبِ.کیونکہ اللہ تعالیٰ غیبوں کو جاننے والا ہے.اور اسے مزید جاننے کی ضرورت نہیں.ان معنوں کو مدنظر رکھتے ہوئے آیت اِذَا مَا ابْتَلٰىهُ رَبُّهٗ فَاَكْرَمَهٗ وَ نَعَّمَهٗ١ۙ۬ فَيَقُوْلُ رَبِّيْۤ اَكْرَمَنِ کا یہ مفہوم ہو گا کہ انسان کی یہ حالت ہے کہ جب اس کا رب اس کے اخلاق کی یا اس کے خیالات کی یا اس کے افکار کی یا اس کی طاقتوں کی اچھائی یا برائی کو ظاہر کرنا چاہتا ہے اس ذریعہ سے کہ اس کا اکرام کرتا ہے اور اسے نعمتیں دیتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے میرا اکرام کیا.خدا تعالیٰ کا طریق یہ ہے کہ جب وہ بندے کے اندرونی ایمان اور اس کے عقیدہ اور اس کے اخلاص کو ظاہر کرنا چاہتا ہے تا اس شخص کو خود بھی پتہ لگ جائے اور دوسرے لوگوں کو بھی.ورنہ اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہی ہوتا ہے تو وہ ایک تواس کا امتحان اس ذریعہ سے لیتا ہے کہ اس کا اکرام کرتا ہے اور اسے نعمتوں پر نعمتیں دیتا چلا جاتا ہے.اسے کہیں سے روپیہ مل جاتا ہے، کسی تجارت میں نفع حاصل ہو جاتا ہے، کہیں دو دو بچے ایک ایک جانور دے دیتا ہے، کہیں اس کے زمین کی پیدا وار میں ترقی ہو جاتی ہے، کہیں اسے گورنمنٹ کی طرف سے کوئی خطاب یا عہدہ مل جاتا ہے.اس وقت وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دی لیکن وہ یہ جو کچھ کہتا ہے اس میں حقیقت نہیں ہوتی.منہ سے تو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے لیکن حقیقت موجود نہیں ہوتی.اگر اس میں کوئی حقیقت ہوتی تو ہر جگہ ظاہر ہوتی.جیسے لمبے قد کا آدمی ایران میں پھرے گا تب بھی وہ لمبا ہو گا، چین میں پھرے گا تب بھی وہ لمبا ہوگا.لیکن اگر وہ کسی جگہ لمبا نظر آتا ہے اور کسی جگہ چھوٹا.تو دو صورتوں میں سے ایک صورت ضرور ہو گی.یا تو دوسرے موقعہ
Page 257
پر کوئی اور آدمی ہو گا اور یا وہ کبھی اونچی ایڑی کا بُوٹ پہن لیتا ہو گا اور کبھی اسے اتار دیتا ہو گا.بہرحال حالتِ مستقلہ ہی انسان کی اصل حالت ہوتی ہے.اگر حالت مستقلہ نہ ہو تو وہ بناوٹی اور مصنوعی طور پر اختیار کی ہوئی ہوتی ہے چنانچہ بندے کے شکر کے مصنوعی ہونے کا ثبوت یہ ہوتا ہے وَ اَمَّاۤ اِذَا مَا ابْتَلٰىهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهٗ١ۙ۬ فَيَقُوْلُ رَبِّيْۤ اَهَانَنِ.اور جب وہ دوسرے رنگ میں اسے ابتلا میں ڈالتا اور اس کے اندرونہ کو ظاہر کرتا اور اس غرض کو پورا کرنے کے لئے اس کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے (قَدَرَ عَلٰی عِیَالِہٖ کے معنے ہوتے ہیں ضَیَّقَ اس نے عیال کا گذارا تنگ کر دیا) اور اسے کوئی نقصان پہنچ جاتا ہے تو اس وقت بجائے اس کے کہ تقویٰ سے کام لے کر وہ نیکی کو خدا کی طرف منسوب کرتا اور نقصان کو اپنی طرف.جب اس پر کوئی بلا اور مـصیبت پڑتی ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے میری اہانت کی اور اس نے مجھے ذلیل کر دیا.یہ ثبوت ہوتا ہے اس بات کا کہ انعام کے وقت اس نے جو کچھ کہا تھا وہ بھی صرف اس کے منہ کی ہی ایک بات تھی.حقیقت اس میں نہیں تھی.اسی لئے قرآن کریم نے وہاں صرف یَقُوْلُ کا لفظ ہی استعمال کیا ہے.یاد رکھو کفر کی بات منہ سے نکلی ہوئی ایک جرم ہے لیکن نیکی کی بات جب دل سے کہی گئی ہو قطعاً کوئی جرم نہیں مگر اس لئے کہ یہ شخص نیکی کی بات منافقت سے کہتا ہے اس کی پہلی بات بھی جرم بن جاتی ہے اور کفر کی بات چونکہ دل سے نکلی ہوئی ہوتی ہے اس لئے وہ تو جرم ہوتی ہی ہے.تفسیر.اس آیت میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ انسان کو اپنی نعمتوں سے نوازتا اور اس پر اپنے ابر کرم کی بارش برساتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے میرا اکرام کیا اور اگر وہ اپنی مشیت کے ماتحت اس پر تنگی کے اوقات لے آئے اور اس کے وسائل معاش کھلے نہ رہیں تو وہ کہتا ہے میرے رب نے میری تذلیل کی.گویانیکی اور بدی دونوں کو وہ خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کرتا ہے اور کہتا ہے میرے ساتھ اچھا سلوک بھی میرے اللہ نے کیا اور میرے ساتھ برا سلوک بھی میرے اللہ نے کیا مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسا کہنا سخت غلطی ہے تم یہ مت کہو کہ عزت بھی خدا کی طرف سے ملتی ہے اور ذلت بھی خدا کی طرف سے ملتی ہے.نیک نتائج بھی وہی پیدا کرتا ہے اوربرے نتائج بھی وہی پیدا کرتا ہے.خیر و شر حاصل ہونے کے متعلق قرآن مجید کا بیان لیکن دوسری جگہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَ اِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَّقُوْلُوْا هٰذِهٖ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ١ۚ وَ اِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَّقُوْلُوْا هٰذِهٖ مِنْ عِنْدِكَ١ؕ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ١ؕ فَمَالِ هٰۤؤُلَآءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُوْنَ يَفْقَهُوْنَ حَدِيْثًا (النساء:۷۹) یعنی جب ان کو کوئی خوشی کی
Page 258
خبر پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے یہ ویسی ہی بات ہے جیسے کہا گیا تھا کہفَاَمَّا الْاِنْسَانُ اِذَا مَا ابْتَلٰىهُ رَبُّهٗ فَاَكْرَمَهٗ وَ نَعَّمَهٗ١ۙ۬ فَيَقُوْلُ رَبِّيْۤ اَكْرَمَنِ.لیکن جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ خدا کی طرف سے نہیں ہو سکتی بندوں کی کارروائیوں کی وجہ سے ہے.اور چونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم مسلمانوں کے حاکم ہیں اور وہی کفر کے مقابلہ میں تدابیر اختیار کرتے رہتے ہیں اس لئے نقصان ان کی طرف منسوب کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ خرابی نعوذ باللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم کی بے تدبیری کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے فرماتا ہے.قُلْ.تو ان لوگوں سے کہہ دے کُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللّٰہِ.تم بالکل جھوٹ بولتے ہوانعام بھی خدا کی طرف سے آتا ہے اور سزا بھی خدا کی طرف سے آتی ہے.فَمَالِ هٰۤؤُلَآءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُوْنَ يَفْقَهُوْنَ حَدِيْثًا.اس قوم کو کیا ہو گیا کہ یہ اتنی موٹی بات بھی نہیں سمجھتی کہ جو کچھ کرتا ہے خدا تعالیٰ کرتا ہے اس لئے تم یہ کہو کہ انعام بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے اور سزا بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے.اب عجیب بات ہے کہ کافروں نے بھی تو یہی کہا تھا کہ عزت اور ذلت دونوںخدا کی طرف سے آتی ہیں.چنانچہ خود قرآن کریم نے ان الفاظ میں ان کے خیالات کا ذکر کیا کہ فَاَمَّا الْاِنْسَانُ اِذَا مَا ابْتَلٰىهُ رَبُّهٗ فَاَكْرَمَهٗ وَ نَعَّمَهٗ١ۙ۬ فَيَقُوْلُ رَبِّيْۤ اَكْرَمَنِ وَ اَمَّاۤ اِذَا مَا ابْتَلٰىهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهٗ١ۙ۬ فَيَقُوْلُ رَبِّيْۤ اَهَانَنِ.جب اس پر انعامات نازل ہوتے ہیں تو کہتا ہے رَبِّيْۤ اَكْرَمَنِ.میرے رب نے میری عزت کی اور جب اس پر ایسی صورت میں ابتلا وارد کرتا ہے کہ اس کا رزق تنگ ہو جاتا ہے تو وہ کہتا ہے رَبِّيْۤ اَهَانَنِ.میرے رب نے میری اہانت کی.اب یہ بات تو وہی ہے جو سورۂ نساء میں بیان کی گئی ہے.مگر آیت زیر تفسیر میں تو یہ فرمایا ہے کہ تم ایسا مت کہو کہ نیکی بھی خدا کی طرف سے ہے اور بدی بھی خدا کی طرف سے ہے.مگر دوسرے مقام پر جب بعض لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ نیکی خدا کی طرف سے ہے اور بدی بندے کی طرف سے.تو ان کو ڈانٹ دیا کہ یہ بڑی خطرناک بات ہے جو تم نے کہی.حقیقت یہ ہے کہ نیکی بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے اور بدی بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے.گویا دونوں آیتوںمیں ایک نمایاں تضاد پایا جاتا ہے.ایک جگہ نیکی اور بدی دونوں کو خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا غلط قرار دیا گیا ہے اور دوسری جگہ نیکی اور بدی دونوں کا انتساب اللہ تعالیٰ کی طرف کیا گیا ہے.تیسری جگہ فرماتا ہے مَاۤ اَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ١ٞ وَ مَاۤ اَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَّفْسِكَ (النساء:۷۹) جو نیکی تجھ کو پہنچے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے وَ مَاۤ اَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَّفْسِكَ اور جو تکلیف تجھ کو پہنچے وہ تیرے نفس کی طرف سے ہے.حالانکہ سورۂ نساء کی پہلی آیت میں یہی بات کفار نے کہی تھی کہ نیکی کا ظہور خدا تعالیٰ
Page 259
کی طرف سے ہے اور تکلیف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے.اور اس پر انہیں تنبیہ کی گئی تھی لیکن اس دوسری آیت میں فرماتا ہے کہ نیکی خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے اور بدی تمہاری طرف سے.(۴) پھر فرماتا ہے مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهٖ وَ مَنْ اَسَآءَ فَعَلَيْهَا١ؕ وَ مَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ (حٰمٓ السّجدۃ:۴۷) نیکی بھی انسان کے لئے ہے اس کی نفس کی طر ف سے آتی ہے اور بدی بھی اسی کی طرف سے پیدا ہوتی اور اس کی سزا اسے مل جاتی ہے وَ مَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ.تیرا رب لوگوں پر ظلم کرنے والا نہیں جو کچھ کرتے ہیں لوگ خود کرتے ہیں.اس جگہ برائی اور بھلائی دونوں کو بندہ کی طر ف منسوب کر دیا ہے.(۵) اسی طرح قارون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں گذرا ہے اس کے متعلق سورۂ قصص میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے دعویٰ کیا اِنَّمَاۤ اُوْتِيْتُهٗ عَلٰى عِلْمٍ عِنْدِيْ (القصص:۷۹) میں نے اپنے علم کے مطابق کام کیا اور مجھے اس کا نتیجہ مل گیا مگر اللہ تعالیٰ نے اسے توبیخ کی اور فرمایا کہ وہ جھوٹ بولتا اور خدا تعالیٰ پر افتراء سے کام لے رہا ہے.اب یہاں بظاہر ساری ہی باتیں الٹ گئیں اور جو کچھ بیان کیا گیا تھا ان سب کی تردید کر دی گئی.جب بندے نے کہا کہ نیکی اور بدی دونوں خدا تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں یہ بات بالکل غلط ہے.جب بندے نے کہا کہ نیکی خدا کی طرف سے اور بدی بندے کی طرف سے آتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ بالکل غلط ہے.کُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللّٰہِ ہر بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، نیکی بھی اسی کی طرف سے آتی ہے اور بدی بھی اسی کی طرف سے آتی ہے.مگر پھر ان دونوں کے خلاف یہ بات بیان کر دی کہ نیکی خدا کی طرف سے اور بدی بندے کی طرف سے آتی ہے.اور آخر میں کہہ دیا کہ نیکی اور بدی دونوں بندے کی طرف سے پیدا ہوتی ہیں.سورۂ فجر میں تو فرمایا کہ عزت اور ذلت دونوں تم نے اللہ تعالیٰ کی طرف کیوں منسوب کیں اور سورۂ نساء میں فرما دیا کہ عزت اور ذلت دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں.ایک کو خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا اور دوسری کو نہ کرنا درست نہیں.تیسرے سورۂ نساء کی اگلی آیت میں ہی فرما دیا کہ عزت خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے اور ذلت اپنے نفس سے.چوتھے سورۂ حٰم سجدہ میں فرمایا کہ دونوں ہی انسان کی طرف سے ہیں.خیر و شر پہنچنے کے متعلق چار نظریے اب بظاہر یہ چار اختلاف ہیں اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر سچ کیا ہے؟ آخر چار ہی صورتیں ہو سکتی ہیں.(۱) یا تو نیکی اور بدی دونوں خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوں.(۲)یا نیکی اور بدی دونوں انسان کی طرف سے ہوں.
Page 260
(۳)یا خیر خدا تعالیٰ کی طرف سے ہو اور شر انسان کی طرف سے.(۴) یا شر خدا تعالیٰ کی طرف سے ہو ا ور خیر انسان کی طرف سے.پانچویں بات تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی.قرآن کریم نے اس امر کو بھی ردّ کیا کہ دونوں خدا تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور اس امر کو بھی ردّ کر دیا ہے کہ دونوں انسان کی طرف سے ہیں اور اس امر کو بھی کہ خیر خدا تعالیٰ کی طرف سے اور شر بندہ کی طرف سے ہے اور اسے بھی ردّ کیا ہےکہ شر خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے اور خیر بندہ کی طرف سے.اس کا حل یہ ہے کہ یہ سب امور الگ الگ زاویہ اور الگ الگ نقطۂ نگاہ کے ماتحت بیان کئے گئے ہیں اور ان میں جو اختلاف نظر آ رہا ہے وہ صرف زاویۂ نگاہ کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے.جہاں کسی بات کو بیان کر کے اس کی تردید کی گئی ہے وہاں اور زاویہ نگاہ ہے اور جہاں اس بات کی تصدیق کی گئی ہے وہاں اور زاویۂ نگاہ ہے اور زاویۂ نگاہ کے اختلاف اور نقطۂ نگاہ کے تغیر سے بہت کچھ تبدیلی ہو جایا کرتی ہے.مثلاً ایک شخص کہتا ہے مجھے نبی جو کچھ کہے گا وہ میں کروں گا یا خلیفۂ وقت جو کچھ کہے گا اس پر عمل کروں گا یا امیر اور پریذیڈنٹ جو کچھ کہے گا وہی کروں گا.اب بظاہر یہ بڑی معقول بات ہے اور جو بھی سنے گا اسے درست قرار دے گا لیکن اگر گھر میں بیٹھے ہوئے کسی شخص کے سامنے روٹی رکھی جائے اور وہ کہے کہ میں اس وقت تک روٹی نہیں کھاؤں گا جب تک نبی یا خلیفہ یا امیر یا پریذیڈنٹ مجھے آ کر نہ کہے تو گو بات وہی ہوگی.مگر نقطۂ نگاہ کے بدل جانے اور اس کے محل میں تبدیلی آ جانے کی وجہ سے ہم اس کی ایک بات کو غلط کہیں گے اور دوسری بات کو ٹھیک کہیں گے یا اگر ایک شخص ہنگامی طور پر کسی چندے کی تحریک کرتا ہے اور لوگوں سے کہتا ہے کہ فلاں غرض کے لئے روپیہ دو اور وہ اسے کہتے ہیں کہ جب تک ہمارا امیر اس چندے میں حصہ لینے کی اجازت نہ دے یا جب تک مرکز کی طرف سے اس بارہ میں باقاعدہ اجازت حاصل نہ کر لی جائے ہم چندہ نہیں دے سکتے تو یہ بالکل صحیح بات ہو گی.اگر اس طرح لوگوں کو چندے لینے کی اجازت دے دی جائے تو مرکزی تحریکات کے لئے لوگوں کے پاس روپیہ نہیں رہ سکتا.لیکن اگر ایک شخص کے پاس سیکرٹری مال یا تحریک جدید کا سیکرٹری چندہ کی وصولی کے لئے جائے اور وہ کہے کہ جب تک خلیفۃ المسیح کا میرے نام خط نہ لاؤ گے یا جب تک بیت المال مجھے نہ لکھے گا میں تمہیں چندہ نہیں دے سکتا تو ہر شخص اس کی بات کو غلط قرار دے گا.اگرچہ پہلے اسی بات کو صحیح سمجھا جا چکا ہوگا.وہ فقرہ ایک اور نقطۂ نگاہ کے ماتحت کہا گیا تھا اور یہ فقرہ ایک اور نقطۂ نگاہ کے ماتحت کہا گیا ہے.چونکہ زاویۂ نگاہ بدل گیا ہے اس لئے دونوں میں سے ایک بات کو ہم درست قرار دیں گے اور دوسری کو غلط.غرض زاویۂ نگاہ کی تبدیلی سے بہت بڑا فرق پیدا ہو جاتا ہے.مثلاً باپ کو جوتی مارنا کتنا خطرناک جرم ہے لیکن
Page 261
فرض کرو باپ آگے بیٹھا ہے اور بیٹا پیچھے ہے اور بیٹے نے یہ دیکھا کہ ایک سانپ اس کے باپ کے کوٹ یا قمیص پر چڑھتا جا رہا ہے اور وہ عین اس کی گردن تک پہنچ گیا ہے وہ سمجھتا ہے اگر میں نے ایک منٹ کی بھی دیر کی تو سانپ اسے کاٹ لے گا.ایسی صورت میں اگر وہ سانپ کو اپنے ہاتھ سے ہٹاتا ہے تو اسے خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں سانپ ہوشیا ر ہو کر میرے باپ کو کاٹ نہ لے.وہ اس کا علاج صرف یہی سمجھتا ہے کہ کسی جھٹکے کے ذریعہ اسے الگ کیا جائے اس وقت جب وہ اپنے دائیں بائیں دیکھتا ہے تو اسے سوائے بوٹ کے اور کوئی چیز نظر نہیں آتی.اس وقت وہ یہ نہیں سوچے گا کہ میں اپنے ابّا جان کو بوٹ کس طرح ماروں بلکہ اگر اسے بوٹ ملے گا تو بوٹ اور اگر جوتی ملے گی تو جوتی سانپ پر زور سے مارے گا اورسمجھے گا کہ اگر میں نے بوٹ یا جوتی نہ ماری تو میرے باپ کو زیادہ نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے.اب دیکھو اس جگہ اس نے اپنے باپ کو جوتی ماری ہوگی مگر لوگ اسے ملامت نہیں کریں گے کہ بڑا خبیث تھا اپنے باپ کو اس نے جوتی مار دی بلکہ ہر شخص اس کی تعریف کرے گا اور کہے گا کہ بڑا عقل مند بیٹا تھا جس نے اپنے باپ کی جان بچا لی.اگر وہ ایسا نہ کرتا تو سانپ اس کے باپ کو ضرور ڈس لیتا گویا ایک ہی فعل ایک جہت سے تو قابل مذمت ہوتا ہے اور دوسری جہت سے قابل تعریف ہوتا ہے.فرض کرو کسی جگہ آگ لگی ہوئی ہو اور ایک شخص مصلّٰی بچھا کر نماز پڑھنے لگ جائے لوگ شور مچا رہے ہوں کہ پانی لاؤ پانی لاؤ، اور یہ بیٹھا تسبیح ہاتھ میں لئے ذکر الٰہی کر رہا ہو تو لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ بڑا نمازی ہے خدا سے بڑی محبت رکھنے والا ہے بلکہ ہر شخص اس کی مذمت کرے گا حالانکہ نماز بڑی اچھی چیز ہے.غرض نقطۂ نگاہ اور محل کے بدلنے سے انسانی اقوال اور افعال کی حیثیت بھی بدل جاتی ہے.یہ بات کہ شر خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے اور خیر بندے کی طرف سے، اس کو تو قرآن کریم نے کلّی طور پر ردّ کر دیا ہے.یہ جائز ہی نہیں کہ کوئی شخص یہ کہے کہ نیکی بندے کی طرف سے آتی ہے اور بدی خدا تعالیٰ کی طرف سے.یہ ہر زاویۂ نگاہ سے بری بات ہے اور اس کی کوئی نیک توجیہ ہو ہی نہیں سکتی.یہ کہ خیر خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے اور شر بندہ کی طرف سے، اس کی تردید قرآن کریم نہیں کرتا بلکہ تائید کرتا ہے جیسا کہ سورۂ نساء میں فرماتا ہے مَاۤ اَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ١ٞ وَ مَاۤ اَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَّفْسِكَ (النساء:۷۹) جو تجھے نیکی پہنچے وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے اور جو شر پہنچے وہ تیرے نفس کی طرف سے ہے اس کی تردید قرآن کریم نے کسی جگہ نہیں کی.بلکہ ہمیشہ اس کی تائید کی ہے اور جو بظاہر تردید معلوم ہوتی ہے وہ بھی تردید نہیں بلکہ تائید ہے.چنانچہ اس سے پہلی آیت میں جو کہا گیا ہے کہ وَ اِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَّقُوْلُوْا هٰذِهٖ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ١ۚ
Page 262
وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَّقُوْلُوْا هٰذِهٖ مِنْ عِنْدِكَ١ؕ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ١ؕ فَمَالِ هٰۤؤُلَآءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُوْنَ يَفْقَهُوْنَ حَدِيْثًا(النساء: ۸۰) جب بھلائی آتی ہے تو کہتے ہیں یہ خدا کی طرف سے ہے اور جب برائی آتی ہے تو کہتے ہیں یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے حالانکہ دونوں خدا کی طرف سے ہیں.اس کا وہ مفہوم نہیں جو مَاۤاَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ١ٞ وَ مَاۤ اَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَّفْسِكَ کا ہے بلکہ اس کا مفہوم بالکل اور ہے.درحقیقت اس آیت میںمنافقین کی اس شرارت کی تردید کی گئی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کوشش کا نیک نتیجہ نکلے وہ کہتے تھے کہ یہ تو اتفاقاً ہے اس میں کسی الٰہی تائید یا آپ کی کسی اعلیٰ تدبیر کا دخل نہیں.مگر وہ الفاظ یہ استعمال کرتے تھے کہ ھٰذِہٖ مِنْ عِنْدِ اللّٰہِ.دراصل یہ ایک محاورہ ہے جو ان لوگوں نے جن کے دلوں میں خدا تعالیٰ پر کامل ایمان نہیں ہوتا اتفاقی امور کے لئے ایجاد کیا ہوا ہے اس سے یہ مراد نہیں ہوتی کہ انہیں خدا تعالیٰ کی ذات پر یقین ہے اور وہ اس کام کو خدا تعالیٰ کی تائید کا نتیجہ سمجھتے ہیں بلکہ یہ محض رسمی رنگ کے الفاظ ہوتے ہیں جو ایمان پر دلالت نہیں کرتے بلکہ اس غرض کے لئے استعمال کئے جاتے ہیں کہ اسے اتفاق قرار دیا جائے.ہمارے ملک میں بھی اتفاقی امور کے متعلق اس قسم کے الفاظ استعمال کئے جاتے ہیں چنانچہ جب کوئی واقعہ ہو تو لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ یہ کام ’’رب سببی‘‘ ہو گیا یا ’’رب سببوں‘‘ فلاں چیز مل گئی ہے حالانکہ ان کے دل میں ذرا بھی خدا تعالیٰ کا خوف اور اس کی خشیت نہیں ہوتی.ذرا بھی ان کو اس بات پر یقین نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کو کامیابی عطا فرمائی ہے.محض رسمی رنگ میں یہ الفاظ ان کی زبان سے نکل جاتے ہیں.اور مراد یہ ہوتی ہے کہ اتفاقیہ طور پر یہ کام ہو گیا ہے.پس یہ الفاظ ان کے کسی ایمان پر دلالت نہیں کرتے بلکہ یہ ایک محاورہ ہے جو لوگوں کی زبان پر چڑھا ہوا ہوتا ہے.فرق صرف یہ ہے کہ ایک مومن جب یہ الفاظ استعمال کرتا ہے تو اس کی مراد حقیقتاً یہ ہوتی ہے کہ خدا تعالیٰ نے مجھ سے یہ نیک معاملہ کیا ہے لیکن ایک کافر یا منافق جب ان الفاظ کو استعمال کرتا ہے تو اس کی مراد صرف یہ ہوتی ہے کہ یہ کام محض اتفاق سے ہو گیا.اس سے زیادہ یہ الفاظ اس کے نزدیک اپنے اندر کوئی معنے نہیں رکھتے یہی بات اللہ تعالیٰ نے اس جگہ بیان فرمائی ہے کہ منافقین کی حالت یہ ہے کہ جب انہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں ھٰذِہٖ مِنْ عِنْدِ اللّٰہِ ’’ رب سببی‘‘ یہ بات ہو گئی ہےیعنی اتفاقی طور پر ایسا ہو گیا ہے پس یہ محض رسمی الفاظ ہیں.ان کے ایمان پر دلالت کرنے والے الفاظ نہیں ہیں چنانچہ اس کا ثبوت یہ ہے کہ وہ نقصان کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے تھے جو بے ایمانی کی علامت تھی.اگر وہ نقصان کو اپنی طرف منسوب کرتے تو اور بات ہوتی مگر وہ نقصان کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم کی
Page 263
طرف منسوب کر دیتے ہیں جو صاف طور پر ان کی بے ایمانی کی علامت ہے.اگر کہو کہ وہ نتائج کے لحاظ سے ہر کام کو خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کر نا پسند کرتے تھے تو پھر سوال یہ ہے کہ نتائج تو سب کے سب خدا تعالیٰ ہی نکالتا ہے پھر وہ یہ کیوں کہتے ہیں کہ نیک نتائج خدا نکالتا ہے اور برے نتائج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم نکالتے ہیں.پس اگر انہوں نے نتائج کے اعتبار سے ایسا کہا تب بھی غلط ہے کیونکہ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ کُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللّٰہِ اچھے نتائج بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدا ہوتے ہیں اور برے نتائج بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدا ہوتے ہیں اس صورت میں انہیں اچھے اور برے دونوں نتائج خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کرنے چاہیے تھے مگر وہ اچھے نتائج خدا تعالیٰ کی طرف اور برے نتائج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیتے تھے اور اگر انہوں نے اچھے اور برے نتائج کو بندے کے عمل کی طرف منسوب کرنا تھا اور ان کا یہ دعویٰ تھا کہ بندہ اچھے عمل کرتا ہے تو اچھے نتائج پیدا ہوتے ہیں، برا عمل کرتا ہے تو برے نتائج پیدا ہوتے ہیں تو اس صورت میں اچھے اور برے دونوں نتائج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہونے چاہیے تھے.اگر اُحد میں کسی غلطی کی وجہ سے بہت سے مسلمان مارے گئے تو آخر بد ر میں مٹھی بھر صحابہؓ کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے ایک بہت بڑے لشکر پر فتح بھی تو پائی تھی اگر وہ بندے کے فعل کو دیکھ رہے تھے اور اسی نقطہ نگاہ سے یہ بات کہہ رہے تھے تو وہ کہتے کہ نیکی بھی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہےاور بدی بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے اور اگر وہ نتائج کے اعتبار کو ملحوظ رکھ کر بات کرتے تو کہتے کہ نیکی بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے اور بدی بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے مگر وہ ان دونوں نقطہ ہائے نگاہ کے خلاف یہ کہتے ہیں کہ نیکی خدا تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے اور بدی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آتی ہے.حقیقت یہ ہے کہ منافقین ایسا کر ہی نہیں سکتے کہ نیکی اور بدی دونوں کو خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیں یا نیکی اور بدی دونوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم کی طرف منسوب کر دیں کیونکہ ان کی غرض تو یہ تھی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت دلوں سے کم کریں اگر وہ کہتے کہ نیک نتائج بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں اور برے نتائج بھی آپ کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں تو لوگوں کے دلوںمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت بدظنی پیدا نہ ہو سکتی کیونکہ زیادہ اچھے نتائج نکلتے تھے اور بہت کم خراب نکلتے تھے.سو ۱۰۰ میں سے اٹھانوے نتائج بہتر ہوتے اور صرف دو۲ نتائج خراب نکلا کرتے تھے.پس اگر وہ ایسا کہتے تو ان کا کام نہ بنتا.لوگ کہتے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم بڑے عقل مند لیڈر ہیں کہ انہوں نے لڑائیوں میں اتنی دفعہ فتح پائی، اتنی دفعہ
Page 264
مالِ غنیمت لیا، اتنے لوگوں کو قید کیا، صرف ایک دو دفعہ اگر لڑائی میں مسلمانوں کونسبتاً زیادہ نقصان پہنچ گیا تو یہ معمولی بات ہے ورنہ چالیس پچاس غزوات میں ہر جگہ ایسا ہی ہوا کہ اگر آپ کا ایک آدمی مارا گیا تو دشمن کے دس آدمی مارے گئے.پس اگر وہ اچھے اور برے دونوں نتائج کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے تو یہ بات آپ کے درجہ اور شان کو بلند کرنے والی ہوتی اور ہر جگہ آپ کی تعریف ہوتی اور اگر وہ نتائج کو خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے اور کہتے کہ نیکی بھی خدا کی طرف سے ہے اور بدی بھی خدا کی طرف سے ہے تب بھی ان کا کام نہ بنتا اور وہ لوگوں کو گمراہ کرنے میں کامیاب نہ ہو سکتے.پس چونکہ ان کی غرض لوگوں کے ایمانوں پر ڈاکہ ڈالنا تھی اس لئے وہ نہ روحانی نقطۂ نگاہ لیتے تھے نہ مادی نقطۂ نگاہ.بلکہ اگر بھلائی آتی تو کہتے یہ اتفاق کی بات ہے اور اگر نقصان پہنچتا تو کہتے یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہوا ہے.فلاں موقع پر بھی نقصان ہوا تھا مگر محمد رسول اللہ ؐ پھر بھی نہ سمجھے اور قوم کو دوبارہ نقصان برداشت کرنا پڑا.پس ان کا یہ اعتراض کسی فلسفہ پر مبنی نہیں تھا بلکہ محض شرارت اور فتنہ و فساد پر اس کی بنیاد تھی اسی لئے خدا تعالیٰ نے اس کی تردید کی ہے ورنہ یہ صحیح ہے کہ خرابی بندے کی غلطی کے نتیجہ میں پیدا ہوتی ہے اور انعام خدا تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے مگر بندے سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ عام مسلمان ہیں جہاں جہاں مسلمانوں کو نقصان پہنچا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی غلطی کی وجہ سے نہیں پہنچا بلکہ بعض جگہ مسلمانوں کے غلط اجہتاد کی وجہ سے جیسے اُحد کی جنگ میں اور بعض جگہ کافروں اور کمزور مسلمانوں کی بزدلی کی وجہ سے جیسے غزوۂ حنین میں.لیکن منافق نہ روحانی نقطۂ نگاہ سے یہ بات کہتے تھے نہ مادی نقطۂ نگاہ سے.صرف شرارت سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے کے لئے ایسا کہتے تھے اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کے قول کی تردید کر دی.اگر کہو کہ ادب کے مقام پر خیر خدا تعالیٰ کی طرف اور شر بندے کی طرف منسوب ہوتی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ان کے دلوں میں ادب ہوتا تو اس صورت میں ان کو شر اپنی طرف یا اتفاق کی طرف منسوب کرنا چاہیے تھا اور انہیں یوں کہنا چاہیے تھا کہ ہم سے غلطی ہوئی جس کا یہ خمیازہ بھگتنا پڑا.محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ بدی کو منسوب نہ کرتے.ادب یہی ہوتا ہے کہ انسان غلطی اپنی طرف منسوب کرتا ہے اور خوبی اپنے افسر کی طرف.مگر وہ خوبی خدا تعالیٰ کی طرف اور بدی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ادب کے طور پر وہ ایسا نہیں کہہ رہے تھے بلکہ محض شرارت اور فساد کی نیت سے ایسا کہتے تھے.اب رہا خیر کو اللہ تعالیٰ کی طرف اور شر کو اپنی طرف منسوب کرنا.اس دعوے کا نقطۂ نگاہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
Page 265
ہر چیز انسان کی بھلائی کے لئے پیدا کی ہے آگے کبھی اپنے فعل کی وجہ سے اور کبھی دشمن کے فعل کی وجہ سے وہ انسان کے لئے بری بن جاتی ہے.مثلاً خدا تعالیٰ نے سنکھیا اس لئے پیدا کیا ہے کہ اگر انسان کو بخار چڑھے تو وہ اس سے فائدہ اٹھائے یا کسی کو خون کے دست آ رہے ہوں تو ہومیو پیتھک ڈوز میں اسے آرسنک دیا جائے تا کہ اس کی پیچش دور ہو جائے اور خون آنا بند ہو جائے یا سنکھیا خدا تعالیٰ نے اس لئے پیدا کیا ہے کہ اگر کوئی کمزور شخص ہو.اس کے جسم میں خون کی کمی ہو.تو وہ سنکھیا استعمال کر کے اپنی کمیٔ خون اور جسم کی کمزوری کو دور کر لے یا اگر اعصاب میں کمزوری پیدا ہو چکی ہو تو سنکھیا استعمال کر کے اعصاب کو مضبوط بنا لیا جائے اسی طرح اور بیسیوں فوائد ہیں جن کے لئے سنکھیا استعمال کیا جاتا ہے مگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان خودکشی کرنے کے لئے سنکھیا کھا لیتا ہے.کبھی جہالت سے بغیر ضرورت اور بغیر ڈاکٹری مشورہ کے ایسی چیزیں استعمال کر لیتا ہے جن میں سنکھیا پڑا ہوا ہوتا ہے، کبھی دشمن اسے زہر دے دیتا ہے اور اس طرح وہ ہلاک ہو جاتا ہے.اب سنکھیا تو خدا تعالیٰ نے خیر کے لئے ہی پیدا کیا تھا مگر اس کے اپنے غلط استعمال کی وجہ سے یا معالج کی بے احتیاطی کی وجہ سے یا دشمن کی شرارت کی وجہ سے وہ خیر اس کے لئے شر بن جاتی ہے یا مثلاً خدا نے لوہا اس لئے بنایا ہے کہ لوگ گنڈاسے بنائیں اور اس سے چارہ کتریں، چاقو تیار کریں اور اس سے قلمیں اور پنسلیں تراشیں، چھرے بنائیں اور ان سے بکرے ذبح کریں، کسیاں بنائیں اور ان سے زمین کھودیں، کدالیں بنائیں اور ان سے سخت پتھریلی زمینیں توڑیں، اسی طرح آرے تیار کریں اور لکڑیوں کو چیریں مگر ایک اور شخص لوہا لے کر اپنے سر پر مارتا ہے اور مر جاتا ہے اب یہ فعل اس کا اپنا ہے اللہ تعالیٰ کا نہیں.اس نے تو بہرحال انسان کے فائدہ کے لئے لوہے کو پیدا کیا تھا اس لئے نہیں پیدا کیا تھا کہ وہ نقصان اٹھائے یا اپنے آپ کو ہلاک کرلے.پس چونکہ خدا تعالیٰ نے ہر چیز انسان کے فائدہ کے لئے پید اکی ہے اگر وہ نقصان اٹھاتا ہے تو اپنی غلطی کی وجہ سے.اس لئے ہر نیکی خدا تعالیٰ کی طرف منسوب ہوتی ہے اور ہر بدی بندے کی طرف منسوب ہوتی ہے.اصل بات یہ ہے کہ جہاں تک نتائج کا سوال ہے یہ امر خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے کیونکہ نتیجۂ شر بھی خدا تعالیٰ پیدا کرتا ہے اور نتیجۂ خیر بھی خدا تعالیٰ ہی پیدا کرتا ہے مگر الزام خدا تعالیٰ پر نہیں آتا اس لئے کہ وہ فعل خدا تعالیٰ نے نہیں کیا بلکہ انسان نے کیا ہے.مثلاً فرض کرو ایک شخص نے مینار سے چھلانگ لگائی اور وہ مر گیا.اب بے شک خدا تعالیٰ نے اس کا گوشت پوست ایسا بنایا تھا کہ اگر وہ اونچی جگہ سے گرے تو مر جائے.اس کے پھیپھڑے اس نے ایسے بنائے تھے کہ اگر ان پر چوٹ آئے تو وہ زخمی ہو جائیں مگر اس کے باوجود خدا تعالیٰ نے اسے گرایا نہیں بلکہ وہ خود گرا ہے.پس جہاں تک نتائج کا سوال ہے وہ خدا تعالیٰ کی طرف منسوب ہوں گے یہ کہا جائے گا کہ
Page 266
خدا تعالیٰ نے اس کا گوشت پوست ایسا ہی بنایا تھا کہ اتنی اونچی جگہ سے چھلانگ لگانے کے نتیجہ میں وہ مر جاتا مگر یہ نہیں کہا جائے گا کہ مینار سے اسے خدا تعالیٰ نے گرایا ہے یا اس کا گوشت پوست اس لئے بنایا تھا کہ مینار سے چھلانگ لگائے اس کا گوشت پوست کسی اور غرض کے لئے بنایا گیا تھا مگر بہرحال خدا تعالیٰ نے ایسا ہی گوشت پوست اسے بخشا تھا جو بلند جگہ سے گرنے کے نتیجہ میں کچلا جائے اور انسان ہلاک ہو جائے مگر اس کے باوجود خدا تعالیٰ پر یہ الزام نہیں آئے گا کہ اس نے ہلاک کیا.غرض جہاں تک نتائج کا سوال ہے اچھے اور برے دونوں خدا تعالیٰ کی طرف منسوب ہوں گے لیکن جہاں تک شر کے الزام کا سوال ہے وہ بندے پر عائد ہو گا لیکن فعلِ بد اور فعلِ خیر دونوں بندے کی طرف منسوب ہوں گے اچھا فعل بھی اسی کی طرف منسوب ہو گا اوربرا فعل بھی اسی کی طرف منسوب ہو گا.اور جہاں تک نتائج کا سوال ہے شر بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے اور خیر بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے.جب ہم نتائج کے لحاظ سے کوئی بات کریں گے تو کہیں گے خدا تعالیٰ کی طرف سے خیر بھی آتی ہے اور خدا تعالیٰ کی طرف سے شر بھی آتی ہے لیکن جب یہ کہا جائے گا کہ برے اور اچھے کام کون کرتا ہے تو ہم کہیں گے چوری بھی بندہ کرتا ہے اور نماز بھی بندہ پڑھتا ہے اور جہاں تک سامانوں کے بالقوہ یا بالفعل ظہور کا سوال ہے یعنی یہ سوال کہ انسان کے اندر قوتیں کس مقصد کے لئے رکھی گئی ہیں؟ اس وقت جب بالقوہ طاقتوں کا سوال ہو گا تو ہم کہیں گے کہ یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور جب ان قوتوں کے بالفعل ظہور کا سوال ہو تو ہم کہیں گے کہ یہ بندے کی طرف سے ہیں اس لئے کہ جہاں تک طاقتوں اور قوتوں کا سوال ہے وہ خیر ہی خیر ہیں اس لئے ہم کہیں گے کہ وہ سب خدا تعالیٰ کی طرف سے ہیں لیکن جہاں تک ان قوتوں کے استعمال کا سوال ہے چونکہ بندے برے کام بھی کر لیتے ہیں اور اچھے بھی.اس لئے اگر ا نسان ان قوتوں کا برا استعمال کرے گا تو شر بندے کی طرف منسوب ہو گا اور اگر وہ ان قوتوں کا نیک استعمال کرے گا تو چونکہ خدا تعالیٰ نے ہی ان قوتوں کو نیکی کے لئے پیدا کیا ہے اس لئے وہ خیر خدا تعالیٰ کی طرف منسوب ہو گا.پس نتائج کے اعتبار سے خیر اور شر دونوں خدا تعالیٰ کی طرف سے ہیں.عمل کے لحاظ سے خیر اور شر دونوں بندے کی طرف سے ہیں بالقوہ طاقتوں کے لحاظ سے خیر خدا تعالیٰ کی طرف منسوب ہو گا اور شر نہیں کیونکہ اس نے کوئی چیز برے استعمال کے لئے پیدا ہی نہیں کی اور بالفعل ظہور کے لحاظ سے خیر خدا تعالیٰ کی طرف اور شر بندے کی طرف منسوب ہو گا کیونکہ خدا تعالیٰ نے ان قوتوں کو کسی شر کے لئے پیدا نہیں کیا تھا.غرض دونوں باتیں خدا تعالیٰ کرتا ہے اور دونوں باتیں بندہ کرتا ہے مگر اس کے باوجود شر بندے کی طرف منسوب ہوتا ہے اور خیر خدا تعالیٰ کی طرف منسوب ہوتا ہے.یہاں انکار انہی معنوں میں کیا گیا ہے جو برے
Page 267
ہیں فرماتا ہے فَاَمَّا الْاِنْسَانُ اِذَا مَا ابْتَلٰىهُ رَبُّهٗ فَاَكْرَمَهٗ وَ نَعَّمَهٗ١ۙ۬ فَيَقُوْلُ رَبِّيْۤ اَكْرَمَنِ کہ جب انسان پر اس کی حقیقت کے اظہار کے لئے اللہ تعالیٰ اکرام وانعام کی بارش نازل فرماتا ہے تو وہ اس حقیقت کو نظر انداز کرتے ہوئے کہتا ہے کہ خدا نے میرا اکرام کیا یعنی میں ایسا ہی تھا کہ خدا تعالیٰ مجھ سے یہ سلوک کرتا.وہ یہ نہیں سمجھتا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں مجھے اس لئے دی ہیں تا ان کے ذریعہ میرا گند یا میری خوبی دنیا پر ظاہر کرے یا مجھے اس لئے دولت دی ہے تا کہ لوگوں کو دکھائے کہ میرا ایمان اتنا مضبوط ہے یا نہیں کہ باوجود دولت ملنے کے میں تکبّر میں مبتلا نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حقوق کو پوری دیانتداری کے ساتھ ادا کرتا رہتا ہوں بلکہ وہ سمجھتا ہے خدا مجھ پر عاشق ہو گیا ہے کہ اتنے بڑے انعام مجھے عطا کرتا جا رہا ہے گویا وہ خدا تعالیٰ کے اکرام اور اس کے انعام سے ایک غلط نتیجہ نکال لیتا ہے.وَ اَمَّاۤ اِذَا مَا ابْتَلٰىهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهٗ١ۙ۬ فَيَقُوْلُ رَبِّيْۤ اَهَانَنِ.اور اگر خدا تعالیٰ کسی وقت رزق کی تنگی سے اس کی آزمائش کرتا ہے تو وہ یہ نہیں سمجھتا کہ خدا تعالیٰ اس ابتلا کے ذریعہ میرے اندرونہ کو ظاہر کرنا چاہتا ہے وہ دنیا کو یا خود مجھے یہ دکھانا چاہتا ہے کہ مشکلات کو کس حد تک برداشت کرنے کی میرے اندر قوت پائی جاتی ہے اور قومی ضرورتوں کے وقت میں اچھا سپاہی ثابت ہو سکتا ہوں یا نہیں.وہ ان حکمتوں میں سے کسی حکمت کو نہیں سمجھتا بلکہ یہ شور مچانا شروع کر دیتا ہے کہ خدا نے مجھے بے عزت کر دیا.گویا دونوں موقعوں پر وہ ایک غلط نقطۂ نگاہ اختیار کر لیتا ہے اس لئے اس کی دونوں باتیں غلط ہوتی ہیں ورنہ حقیقت کے لحاظ سے یہ دونوں باتیں صحیح ہیں کہ کبھی اللہ تعالیٰ انسان کی اس رنگ میں آزمائش کرتا ہے کہ اس پر انعام و اکرام نازل کرتا ہے اور کبھی اس رنگ میں آزمائش کرتا ہے کہ اسے مشکلات اور مصائب اور تنگئ رزق کا سامنا کرنا پڑتا ہے.ایک سچا مومن دونوں حالتوں میں ثابت قدم رہتا ہے مگر کافر کی یہ حالت ہوتی ہے کہ انعام و اکرام کے وقت وہ کہتا ہے رَبِّيْۤ اَكْرَمَنِ خدا نے میرا اکرام کیا حالانکہ خدا تعالیٰ اس ذریعہ سے اس کا امتحان لے رہا ہوتا ہے اور تنگئ رزق کے وقت وہ کہتا ہے رَبِّيْۤ اَهَانَنِ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا حالانکہ اس ذریعہ سے وہ اس کے اندرونہ کو بے نقاب کر رہا ہوتا ہے.گویا یہ دونوں ابتلائی مقام ہوتے ہیں جزا و سزا کے مقام نہیں ہوتے.جب اس پر انعامات کے رنگ میں بارش نازل ہو رہی ہوتی ہے اس وقت بھی وہ ابتلا کے نیچے ہوتا ہے اور جب اس پر تنگئ رزق کا دَور ہوتا ہے اس وقت بھی وہ ایک ابتلا کے نیچے ہوتا ہے.یہ نہیں ہوتا کہ انعامات اسے کسی اعلیٰ درجہ کے کام کی جزا کے طور پر دیئے جا رہے ہوں یا تنگئ رزق کسی جرم کی سزا کے طور پر اس پر حاوی ہو دونوں حالتیں ابتلائی ہوتی ہیں اور دونوں حالتوں میں اس کی
Page 268
حقیقت کو خود اس کے نفس پر اور دوسرے لوگوں پر ظاہر کرنا مقصود ہوتا ہے.اس حقیقت کو کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات اور اس کی طرف سے آنے والی تکالیف کے سلسلہ میں دو قسم کے مقام ہوتے ہیں ایک مقام ابتلائی ہوتا ہے اور ایک مقامِ جزا وسزا ہوتا ہے یعنی کبھی ابتلا کے طورپر انعامات نازل ہوتے ہیں اور کبھی جزائے خیر کے طور پر انعامات نازل ہوتے ہیں.اسی طرح کبھی ابتلا کے طور پر دکھ وارد ہوتے ہیں اور کبھی سزا کے طور پر مختلف تکالیف کے دَور آتے ہیں.اس جگہ صرف ابتلائی مقامات کا ہی ذکر کیا جا رہا ہے جزا و سزا والے مقام کا ذکر نہیں کیا گیا.اسی لئے اللہ تعالیٰ انسان کو مجرم قرار دیتا ہے اور فرماتا ہے ہم اس کا امتحان لینے کے لئے اسے انعامات دیتے ہیں تو وہ کہتا ہے میرے رب نے میرا اکرام کیا.گویا ان انعامات پر اس کا حق تھا اور خدا تعالیٰ کو یہی چاہیے تھا کہ اس کا اکرام کرتا.وہ یہ نہیں سمجھتا کہ میں نے تو کوئی نیک کام کیا نہیں اور یہ کہ یہ نعمتیں تو اس کے امتحان کا ایک ذریعہ ہیں.اس کے مقابلہ میں جب تکالیف کے ذریعہ اس کا امتحان لیا جاتا ہے تو وہ کہہ دیتا ہے رَبِّيْۤ اَهَانَنِ میرے رب نے میری ہتک کر دی.میرے مقام کو اس نے نظر انداز کر کے اس نے مجھے بے عزت کردیا.اگر وہ یہ کہتا کہ میرے جرموں کی وجہ سے خدا تعالیٰ کی طرف سے مجھے یہ سزا ملی ہے یا بجائے اَھَانَنِ کہنے کے وہ کہتا ہے کہ عَذَّبَنِیْ میرے رب نے میرے گناہوں کی پاداش میں مجھے عذاب میں مبتلا کر دیا تو خواہ ابتلائی مقام ہونے کی وجہ سے اس کی یہ بات بھی غلط ہی ہوتی مگر پھر بھی وہ مجرم نہ بنتا مگر وہ تو یہ کہتا ہے رَبِّيْۤ اَهَانَنِ میں اس بات کا مستحق تھا کہ مجھے عزت دی جاتی مگر میرے رب نے مجھے رسوا کر دیا.اصل بات یہ ہے کہ ابتلائی صورتیں اور رنگ کی ہوتی ہیں اور جزا و سزا کی صورتیں اور رنگ کی ہوتی ہیں مثلاً ہر نبی کو خدا تعالیٰ عزت دیتا اور اس کے مقاصد میں اسے کامیابی عطا کرتا ہے اور کئی ایسے انبیاء ہیں جنہیں اس نے علاوہ روحانی حکومت کے جسمانی باد شاہت بھی عطا کی.مثلاً حضرت موسٰی، حضرت داؤدؑ اور حضرت سلیمانؑ کے ہاتھ میں بادشاہت آئی مگر یہ بادشاہت ابتلا کے طور پر نہیں تھی بلکہ انعام کے طور پر ان کے کام کو تقویت پہنچانے کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئی(۱.النمل:۱۷تا۲۰ ۲.صٓ:۱۸تا۲۱ اور ۳۱تا۳۶ ۳.استثناء باب ۲ آیت ۱۱،۱۲ ۴.ا.سلاطین باب ۱۱، ۱۲).یا مثلاً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بادشاہت نہ ملتی تو آپ قرآنی شریعت کو عملی رنگ میں کس طرح رائج کرتے پس آپ کو اور بعض دوسرے انبیاء کو جو حکومت ملی وہ ایک ہتھیار کے طور پر تھی اور ضمنی چیز تھی ابتلا نہیں تھا.ابتلا ہمیشہ اس لئے آتا ہے تاکہ انسان کے اخلاق ظاہر کئے جائیں مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے
Page 269
اخلاق تو پہلے ہی ظاہر تھے آپؐنے سَرَّآء میں بھی خدا تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کیا اور ضَرَّاء میں بھی اس کی رضامند ی کی راہوں کو اختیار کیا.آپ کے پاس دولت آئی تو وہ آپ نے سب کی سب بنی نوع انسان کے فوائد کے لئے لٹا دی اور خود اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا.اس کے مقابلہ میں آپ پر مصائب بھی آئے.کئی قسم کے دکھ بھی آپ کو برداشت کرنے پڑے مگر ہمیشہ آپ نے صبر سے کام لیا.ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان کے پاس سے گذر رہے تھے کہ آپ نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ ایک قبر پر کھڑی رو رہی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا.بی بی صبر کر.اس نے کہا اگر تیرے بچے مرتے تو میں دیکھتی کہ تو کس طرح صبر کرتا.صبر کی نصیحت تو اسی لئے کر رہا ہے کہ یہ میرا بچہ تھا تیرا بچہ نہیں تھا.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا.اے عورت میرے سات مرچکے ہیں مگر میں نے ہر بچے کی وفات پر صبر سے کام لیا ہے.یہ کہہ کر آپ چل پڑے بعد میں کسی نے اسے بتایا کہ بدبخت تجھے پتہ بھی ہے تجھے یہ بات کہنے والا کون تھا؟ اس نے کہا مجھے تو پتہ نہیں.اس نے کہا یہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے یہ سنتے ہی وہ آپ کے مکان پر آئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ میں نے صبر کیا.آپ نے فرمایا اَلصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَۃِ الْاُوْلٰی(صحیح بخاری کتاب الـجنائز باب زیارۃ القبور).صبر تو ابتدائی حالت میں ہوتا ہے بعد میں تو رو دھو کر صبر آ ہی جاتا ہے.غرض وہ حالتیں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آئیں جن میں انسان جزع فزع کرنے لگ جاتا ہے مگر آپ نے ان حالات میں بھی صبر کیا اور یہی کہا کہ ہم اس کی مشیت پر راضی ہیں.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ابراہیم جب فوت ہونے لگا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم اس وقت پاس موجود تھے اس کی تکلیف اور کرب کو دیکھ کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے.کسی نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی روتے ہیں آپ نے فرمایا آنکھ کا آنسو بہانا اور ہے ورنہ ہمیں خدا تعالیٰ کے فعل پر کوئی اعتراض نہیں ہم سمجھتے ہیں کہ اس نے جو کچھ کیا ہے ٹھیک کیا ہے.تو ابتلا اور ہوتے ہیں اور جزا اور ہوتی ہے اور بعض جزائیں تو ایسی ہوتی ہیں جو اعلیٰ درجہ کے روحانی مقامات حاصل کرنے کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام کے طور پر ملتی ہیں جیسے حضرت سید عبدالقادر صاحب جیلانی فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاتا جب تک خدا مجھے نہیں کہتا کہ اے عبدالقادر تجھے میری ذات ہی کی قسم کہ یہ کھانا کھا اور میں کپڑا نہیں پہنتا جب تک مجھے خدا نہیں کہتا کہ اے عبدالقادر تجھے میری ذات ہی کی قسم کہ یہ کپڑا پہن(قلائد الجواھر صفحہ ۲۸ علامہ شیخ محمد بن یحییٰ الحنبلی).یہ ابتلا والا مقام نہیں بلکہ ایک روحانی عہدہ حاصل کرنے کا انعام ہے.ان لوگوں کو سَرَّآء اور ضَرَّآء میں سے گذار کر اللہ تعالیٰ ان کے اخلاق اور ان کے
Page 270
اندرونہ کو دنیا پر اچھی طرح ظاہر کر دیتا ہے اس لئے یہ ضرورت نہیں رہتی کہ ان پر ابتلا وارد کئے جائیں لیکن عام لوگوں کی یہ حالت نہیں ہوتی.ان کے دل پر کبھی گناہوں کی وجہ سے اتنا زنگ لگ جاتا ہے کہ نہ خدا تعالیٰ کی طرف سے آنے والی فراخی کا ان پر کوئی اثر ہوتا ہے اور نہ اس کی طرف سے آنے والی مشکلات ان میں کوئی تغیر پیدا کرتی ہیں.وہ اندھے پیدا ہوتے ہیں اور اندھے ہونے کی حالت میں ہی اس جہان سے گذر جاتے ہیں.ایسی ہی روحانی نابینائی رکھنے والوں کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر کیا ہے اور بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ ابتلا کے طور پر انہیں فراخی دیتا ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں خدا نے ہماری قدر کی حالانکہ ان کے اعمال ایسے نہیں ہوتے کہ اللہ تعالیٰ ان پر انعام کرے.بسا اوقات وہی دولت اور عزت ان کو جہنم میں لے جانے کا باعث بن جاتی ہے اسی طرح جب ان پر تنگئ رزق کا دَور آئے تو کہنے لگ جاتے ہیں خدا نے ہمیں بے عزت کر دیا گویا دونوں حالتوں میں وہ اس کی حکمتوں سے آنکھ بند رکھتے اور روحانی موت کا شکار ہو جاتے ہیں.قرآن کریم میں ان لوگوں کی اصل کیفیت کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا گیا ہے فرماتا ہے وَ اِذَا قِيْلَ لَهُمْ اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ١ۙ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَنُطْعِمُ مَنْ لَّوْ يَشَآءُ اللّٰهُ اَطْعَمَهٗۤ١ۖۗ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ(یٰسٓ:۴۸) یعنی جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے سے دوسرے مستحقین پر خرچ کرو تو وہ مومنوں سے کہتے ہیں کہ کیا تم چاہتے ہو کہ ہم انہیں کھانا کھلائیں جنہیں خدا نے کھانا نہیں کھلایا حالانکہ وہ چاہتا تو انہیں خود رزق دے سکتا تھا.پس ہمیں یہ نصیحت کر کے کہ ہم ان کو دیں جن کو خدا تعالیٰ نہیں دینا چاہتا تم ثابت کر رہے ہو کہ تم بڑے ہی گمراہ ہو.اس آیت نے آیت زیر بحث کی تشریح کر دی ہے ان کفار کا نقطۂ نگاہ یہ ہے کہ ہم مستحق انعامات ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے اور دوسرے لوگ مستحق نہیں اس لئے انہیں نہیں دیتا اور چونکہ خدا تعالیٰ کے فعل نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ مستحق انعام نہیں اس لئے ہمارا بھی فرض ہے کہ انہیں نہ دیں.یہ ظاہر ہے کہ جس کا یہ نقطۂ نگاہ ہو اس کے دل میں انعام پر اللہ تعالیٰ کا شکر پیدا نہ ہو گا.اور اگر کوئی تکلیف آئے گی تو شکوہ پیدا ہو گا کہ خدا تعالیٰ نے ہمارا مناسب اعزاز نہیں کیا اور ہمارے درجہ کا خیال نہیں رکھا.
Page 271
كَلَّا بَلْ لَّا تُكْرِمُوْنَ الْيَتِيْمَۙ۰۰۱۸ (یوں) ہرگز نہیں بلکہ تم (قصور وار ہو کہ)یتیم کی عزت نہیں کرتے.وَ لَا تَحٰٓضُّوْنَ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِۙ۰۰۱۹ اور مسکین کو کھانا کھلا٭نے کی ایک دوسرے کو ترغیب نہیں دیتے.حلّ لُغات.تَحٰٓضُّوْنَ.تَحٰٓضُّوْنَ : حَاضََّّ سے جمع مخاطب کا صیغہ ہے اور حَاضَّہُ عَلَیْہِ کے معنے ہوتے ہیں حَثَّ کُلُّ وَاحِدٍ مِّنْـھُمَا صَاحِبَہٗ.دو شخصوں میں سے ہر ایک نے دوسرے کو کسی کام کے کرنے کی رغبت دلائی (اقرب ) پس لَا تَحٰٓضُّوْنَ کے معنے ہوں گے تم رغبت نہیں دلاتے.تفسیر.فرماتا ہے کَلَّا یوں نہیں جو تم خیال کرتے ہو کہ تم خاص طور پر دولت کے مستحق تھے اس لئے تم کو دولت ملی تھی اور خدا تعالیٰ کی دوسری مخلوق مستحق نہیں تھی اس لئے اسے نہیں ملی اور یہ کہ جب تم کو ابتلاءِ تکلیف آتا ہے تو وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے تمہارے حق میں بے انصافی ہوتی ہے بلکہ بات یہ ہے کہ تم کو دولت ملی تھی کہ تم غرباء پر خرچ کرو اور اس طرح ایک نیک برادری دنیا میں قائم ہو مگر بجائے اس کے تم نے تکبّر شروع کیا اور غریبوں کی خبرگیری ہی سے غفلت نہیں برتی بلکہ ان کو ذلیل بھی کیا کہ تم اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں مستحق نہیں ہو اور یتیموں کی عزت نہ کی بلکہ انہیں ذلیل سمجھا اس لئے خدا تعالیٰ نے بھی تم کو ذلیل کیا اگر تم دولت ملنے پر یہ سمجھتے کہ خدا تعالیٰ نے یہ دولت اس لئے دی ہے کہ وہ دیکھے کہ تم یتیموں کی خبر گیری کرتے ہو یا نہیں اور تم ایک دوسرے سے کہتے ہو یا نہیں کہ خدا نے جب ہمیں روپیہ دیا ہے تو آؤ ہم غرباء کی خبرگیری کریں.ہم بھوکوں کو کھانا کھلائیں ہم ننگوں کا سردیوں میں ننگ ڈھانکیں.مگر جب اس نے تمہیں نعمتیں دیں توبجائے اس کے کہ تم یہ سمجھتے کہ خدا تعالیٰ نے یہ نعمتیں ہمیں اس لئے دی ہیں کہ لوگوں پر خرچ کی جائیں ان کی ضروریات کو پورا کریں اور ان کے دکھوں کو دور کریں تم نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ رَبِّيْۤ اَكْرَمَنِ خدا کا ہمارے ساتھ کوئی خاص جوڑ ہے کہ اس نے یہ نعمتیں ہمیں دی ہیں اَوروں کو نہیں دیں.تم نے یتیموں اور مسکینوں کی ذرا بھی پروا نہ کی اور تم نے اپنے متعلق یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ ہم خدا کے خاص محبوب اور پیارے ہیں کہ اس نے ہمیں تو ان انعامات سے نوازا مگر دوسروں کو محروم رکھا، بجائے اس کے کہ تم یہ سمجھتے کہ تمہیں یتیموں کی نوٹ.طَعَامُ الْمِسْكِيْنِمیں طَعَامُ.اِطْعَامٌ کے مصدر کے طور پر استعمال ہوا ہے اسی لئے اس کے معنے کھانا کھلانے کے کئے گئے ہیں.
Page 272
پرورش اور مساکین کی خبر گیری کے لئے یہ نعمتیںدی گئی ہیں تم نے ان نعمتوں کو اپنا حق قرار دے کر ان کی طرف سے اپنی آنکھیں بالکل موند لیں اور ان کی ضروریات کے لئے ایک پیسہ خرچ کرنابھی روا نہ رکھا.تمہارے سامنے کئی یتیم بچے بھوک سے مرتے رہے، کئی مساکین بھیک مانگتے اور دربدر ٹھوکریں کھاتے رہے مگر تم نے ان کی طرف ذرا بھی توجہ نہ کی بلکہ اسی خیال میں مست رہے کہ ہم بڑے آدمی ہیں.وَ تَاْكُلُوْنَ التُّرَاثَ اَكْلًا لَّمًّاۙ۰۰۲۰ اور ورثہ کا مال سب کا سب (عیش میں) اڑا جاتے ہو.حلّ لُغات.تُرَاثٌ.تُرَاثٌ: وَرِثَ کا مصدر ہے نیز اس کے معنے ہیں مَایَـخْلُفُہُ الرَّجُلُ لِوَرَثَتِہٖ وہ مال جو آدمی اپنے وارثوں کے لئے چھوڑ جاتا ہے (اقرب) لَمًّا.لَمًّا: قَالَ الْفَرَّاءُ اَیْ شَدِیْدًا وَفِی الصِّحَاحِ اَیْ نَصِیْبَہٗ وَنَصِیْبَ صَاحِبِہٖ(اقرب).فرّاء کہتے ہیں کہ لَمًّا کے معنے شدیدکے ہیں اور آیت کا مطلب یہ ہے کہ تم سارے کا سارا مال کھا جاتے ہو یا وہ مال تمہارے قبضہ میں آتا ہے تو تم اسے بالکل چٹ کر جاتے ہو اس میں سے کچھ باقی نہیں رہنے دیتے.لیکن صحاح میں یہ لکھا ہے کہ لَمًّا کے معنے یہ ہیں کہ تم اپنا حصہ بھی کھا جاتے ہو اور دوسروں کا حصہ بھی ہضم کر جاتے ہو(اقرب) گویا یہی نہیں کہ تم صرف اپنا حصہ لینے پر اکتفا کرو بلکہ تم اپنا حصہ بھی چٹ کر جاتے ہو اور یتامٰی و مساکین یا دوسرے بھائیوں کا جو حصہ ہو وہ بھی کھا جاتے ہو.تفسیر.فرماتا ہے تم اپنے اعمال کی طرف دیکھو کہ تمہاری شامتِ اعمال تمہارے لئے کیا کیا رنگ پیدا کر رہی ہے.تم میں بجائے اس کے کہ کوئی نیک خُلق پیدا ہوتا اور تم یتامٰی اور مساکین کی خبرگیری کرتے تم نے دولت ملنے پر اسراف سے کام لینا شروع کر دیا اور اپنے روپیہ کو بالکل برباد کر دیا اس کے بعد بجائے اس کے کہ تم یہ سمجھتے کہ ہم اپنے گندے افعال کی وجہ سے اس غربت کو پہنچے ہیں اور خدا نے اس ذریعہ سے ہمیں ہوشیار کیا ہے اور آئندہ کے لئے نصیحت کر دی ہے کہ تمہیں اسراف نہیں کرنا چاہیے بلکہ روپیہ کو محفوظ رکھنا چاہیے تم نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ رَبِّيْۤ اَهَانَنِ ہماری تو عزت ہونی چاہیے تھی مگر خدا تعالیٰ نے ہمیںرسوا کر دیا حالانکہ خدا تو تمہیں سبق دینا چاہتا تھا ورنہ تم نے ایسے کون سے کام کئے تھے کہ خدا تعالیٰ تمہیں عزت دیتا.یہ خدا تعالیٰ کا احسان تھا کہ اس نے
Page 273
تمہیں نعمتیں دیں اور اس لئے دیں کہ تم غریبوں پر خرچ کرو مگر تم نے روپوں کو اپنی جیب میں ڈالا.یتامیٰ ومساکین کی طرف سے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور شراب اور ناچ گانوں میں اپنی دولت کو برباد کرنا شروع کر دیا اور جب تمہاری دولت سب برباد ہو گئی تم یہ شور مچانے لگ گئے کہ خدا نے ہمیں رسوا کر دیا.بجائے اس کے کہ ان تمام حالات کو تم اصل روشنی میں دیکھتے تم نے الٹا اسے غلط رنگ دے دیا.کیا تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ تمہاری حالت کس قدر گر چکی ہے.کتنی کمینگی اور بے حیائی تم میں پیدا ہو چکی ہے تم یتیموں کا مال لیتے ہو اور اسے شیرمادر کی طرح ہضم کر جاتے ہو.تمہیں ورثہ میں بڑی بڑی جائیدادیں ملتی ہیں، زمینیں ملتی ہیں، کوٹھیاں ملتی ہیں، روپیہ ملتا ہے مگر تم وہ تمام جائیداد عیاشی میں برباد کر دیتے ہو.باپ روپیہ کما کما کر تھک جاتا ہے اور تم صاحبزادے بن کر اس کا سب مال اڑا دیتے ہو اور پھر یہ کہتے ہو لوگ ہماری عزت نہیں کرتے.وہ تمہاری کیوں عزت کریں.جانتے ہیں کہ تمہارا برا حال ہے.بجائے اپنی جائیداد کو بڑھانے کے اور بجائے غریبوں کی خبرگیری کرنے کے تم میں سے کوئی اچھے کھانے کھانے لگ جاتا ہے، کوئی اچھے لباسوں پر اپنا روپیہ برباد کر دیتا ہے، کوئی شراب میںمشغول ہو جاتا ہے، کوئی ناچ گانوں میں اپنی عمر ضائع کر دیتا ہے، کوئی عیاشی میں مبتلا ہو جاتا ہے اور پھر زبانوں پر یہ شکوہ ہوتا ہے کہ لوگ ہماری عزت نہیں کرتے.ہم اتنے بڑے تھے، اتنے بڑے خاندان میں سے تھے، معلوم نہیں کیا ہو گیا.وہ حیران ہوتے ہیں اور پھر خود ہی کہتے ہیں کہ ’’کچھ اللہ ولوںوگ گئی اے‘‘ یعنی خدا کی طرف سے اس کی لعنت کی مار ہم پر آپڑی ہے ورنہ ہماری عزت میں کیا شبہ تھا.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تمہارا باپ مالدار تھا تو تمہیں اس سے بھی اونچی سیڑھی پر چڑھنا چاہیے تھا اگر اس نے ایک ہزار روپیہ کمایا تھا تو چاہیے تھا کہ تم دس ہزار روپیہ کماتے اور بنی نوع انسان کی بہتری کے لئے خرچ کرتے نہ یہ کہ اس روپیہ کو تعیش میں برباد کر دیتے اور بھیک مانگنے لگ جاتے.تم نے خود اپنے نفس کی اہانت کی اور اپنے آپ کو لوگوں کی نگاہ میں گرا دیا اس لئے تم خدا تعالیٰ کی نظر سے بھی گر گئے اور اس کے بندوں کی نظر سے بھی گر گئے.یا اگر تم پر تکلیف کی بعض گھڑیاں آئی تھیں تو اس لئے کہ تم ہوشیار ہو جاؤاور اپنی کوتاہیوں کا ازالہ کر لو.مگر تم اور بھی نیچے پھسلتے چلے گئے.چونکہ لَمًّا کے معنے دوسرے کا حصہ لے لینے کے بھی ہیں اس لئے اس آیت میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ انسان کو جو دولت ملتی ہے وہ صرف اسی کا حصہ نہیں ہوتا اس میں دوسرے بنی نوع انسان کا بھی حصہ ہوتا ہے لیکن بعض لوگ اس دولت کو صرف اپنے نفس پر خرچ کر دیتے ہیں اور دوسروں کا حق کھا جاتے ہیں.
Page 274
وَّ تُحِبُّوْنَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّاؕ۰۰۲۱ اور تم مال سے بے انتہا محبت کرتے ہو.حلّ لُغات.جَمًّا.جَمًّا: اَلْـجَمُّ کے معنے ہیں اَلْکَثِیْرُ مِنْ کُلِّ شَیْءٍ بہت سی چیز (اقرب) نیز کہتے ہیں جَاءُ وْاجَـمًّا غَفِیْـرًا اور معنے یہ ہوتے ہیں جَاءُوْا بِـجَمَاعَتِـھِمْ.اَلشَّـرِیْفُ وَالْوَضِیْعُ وَلَمْ یَتَخَلَّفْ اَحَدٌ وَکَانَتْ فِیْـھِمْ کَثْرَۃٌ یعنی سب لوگ اکھٹے ہو کر آ گئے چھوٹے بھی اور بڑے بھی.کوئی بھی پیچھے نہ رہا اور اسی طرح لوگوں کی کثرت ہو گئی (اقرب) تفسیر.فرماتا ہے تمہاری حالت یہ ہے کہ تم مال کو لپیٹ کر بیٹھ جاتے ہو خدا تعالیٰ نے تو تمہیں اس لئے مال دیا تھا کہ تم اسے تجارت میں لگاؤ یا صنعت وحرفت کو فروغ دو یا غریبوں کی خبر گیری کرو مگر تم اسے بند کر کے بیٹھ جاتے ہو.اسی طرح اس کے یہ بھی معنے ہیں کہ تم مال سے ایسی محبت کرتے ہو کہ اچھے اور برے کی تمیز تم میں باقی نہیں رہی.تمہارے پاس حرام مال آتا ہے تو تم حرام لے لیتے ہو حلال آتا ہے تو حلال لے لیتے ہو.ادنیٰ چیز آتی ہے تو ادنیٰ لے لیتے ہو اعلیٰ چیز آئے تو اعلیٰ لے لیتے ہو.تمہیں صرف مال سے غرض ہوتی ہے اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ وہ مال تمہیں ملا کہاں سے اور کس طرح سے.اوپر کی آیات میں چار امور بیان کئے گئے ہیں جو کفار میں پائے جاتے تھے اور یہی چار امور ایسے ہیں جن سے قومیں تباہ ہوتی ہیں.اوّل یتامٰی کی خبر گیری نہ کرنا.فرماتا ہے ان لوگوں کی حالت یہ ہے کہ جب انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی انعام ملتا ہے تو کہتے ہیں ہم خدا کے حضور خاص شان رکھتے ہیں اور جب ان پر اس رنگ میں ابتلا وارد ہوتا ہے کہ ان کی مالی حالت ناقص ہو جاتی ہے اور ان پر تنگ دستی کے ایام آ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں خدا نے ہماری اہانت کر دی.گویا دونوں صورتوں میں وہ عزت اپنی طرف منسوب کرتے ہیں.عزت آتی ہے تو کہتے ہیں ہمارا اکرام ہونا ہی چاہیے تھا اور اگر اہانت آتی ہے تو کہتے ہیں ہماری تو عزت ہونی چاہیے تھی خدا نے غلطی سے ہمیں ذلیل کر دیا.اللہ تعالیٰ ان امور کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ یہ بات درست نہیں.اصل حقیقت یہ ہے کہ تمہاری تباہی کے سامان تمہارے اندر ہی موجود ہیں اور انہی کے ذیعہ سَوطِ عذاب نازل ہوا کرتا ہے یعنی اندرونی طور پر بعض ایسی قوتیں
Page 275
ہوتی ہیں جو انسان کوتباہی کی طرف لے جاتی ہیں اور تباہی کے وہ سب موجبات تم میں پائے جاتے ہیں.اس لئے اگر تم پر تباہی نہ آئے تو اور کس پر آئے.چنانچہ قومی تباہی کے چار بڑے بڑے اسباب بیان کئے گئے ہیں جن میں سے پہلا اور اہم سبب یتامیٰ کی خبر گیری نہ کرنا ہے.بظاہر یہ ایک روحانی اور دینی کام معلوم ہوتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ قومی ترقی اور اس کے تنزّل کے ساتھ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے.اگر یتامیٰ کی خبر گیری نہ کی جائے، ان کی پرورش کو نظر انداز کر دیا جائے اور ان کو دربدر دھکے کھانے پر مجبور کیا جائے تو دنیا میں کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی.دنیا میں بڑے سے بڑے کام قربانی چاہتے ہیں اور جب تک بڑی بڑی قربانیاں نہ ہوں اس وقت تک بڑے بڑے کام بھی نہیں ہوتے.اور بڑی بڑی قربانیاں دوہی قسم کی ہوتی ہیں یا مالی یا جانی.مگرہم دیکھتے ہیں انسان اپنے لئے تو تکلیف برداشت کر لیتا ہے لیکن جب اسے خیال آتا ہے کہ میرے بال بچوں کا کیا بنے گا تو بہت سے لوگ بزدل بن جاتے ہیں اور قربانی کے میدان سے اپنے قدم کو پیچھے ہٹا لیتے ہیں.اگر کسی قوم میں یتامیٰ کی خبرگیری پوری طرح پائی جاتی ہو تو یہ ممکن ہی نہیں کہ جانی اور مالی قربانیوں کے وقت اس قوم کا کوئی ایک فرد بھی پیچھے رہے اور اپنے آپ کو قربانی کے لئے پیش نہ کرے بلکہ وہ ہنستا ہوا آگے بڑھے گا اور ہر قسم کے شدائد کو خوشی سے برداشت کرنے کے لئے تیار ہو جائے گا.اگر لوگ روزانہ اپنی آنکھوںسے یہ نظارہ دیکھیں کہ فلاں شخص مر گیا تو اس کے یتیم بچوں کو فلاں امیر لے گیا اور اس نے اپنے بچوں کی طرح اپنے گھر میں رکھ لیا، وہ ان میں اور اپنے بچوں میں کوئی فرق نہیں کرتا، وہ انہیں تعلیم دلا رہا ہے، انہیں اچھے سے اچھا کھانا کھلا رہا ہے، انہیں اچھے سے اچھا لباس پہنا رہا ہے تو جب بھی قربانی کا سوال پیدا ہو گا ہر شخص آگے بڑھے گا اور کہے گا اگر میری جان بھی جاتی ہے تو بےشک جائے مجھے اس کی پروا نہیں.فلاں شخص مر گیا تھا تو اس کے بچے فلاں قومی بھائی لے گیا اور اس نے انہیں اپنے بچوں کی طرح پالنا شروع کر دیا.فلاں شخص مر گیا تو اس کے بچوں کو فلاں شخص لے گیا اور ان کے اخراجات کا متکفّل ہو گیا اگر میں بھی مر گیا تو کیا ہوا میرے بچوں کی قوم نگران ہو گی اور وہ مجھ سے زیادہ بہتر رنگ میں ان کی تربیت کا فرض سرانجام دے گی.یہ احساس اگر ہر فرد کے دل میں پیدا ہو جائے اور یتامیٰ کی خبر گیری قومی طور پر کسی جماعت میں پائی جائے تو وہ جماعت کبھی مٹ نہیں سکتی.وہ جماعت کبھی بڑی سے بڑی قربانی سے دریغ نہیں کر سکتی.قربانیوں سے ہچکچاہٹ محض اس لئے پیدا ہوتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم مر گئے تو ہمارے بچے خا ک میں مل جائیں گے ان کا کوئی نگران نہیں ہو گا، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہو گا، لوگ انہیں ڈانٹیں گے، ان سے نوکروں کی طرح کام لیں گے، ان کو بوٹ کی ٹھوکروںسے ماریں گے، انہیں کھانے کے لئے سوکھے ٹکڑے اور پہننے کے لئے
Page 276
پھٹے پرانے کپڑے دیں گے، ان کے سروں پر محبت کا ہاتھ نہیں رکھیں گے، ان کو پیار کی نگاہوں سے نہیں دیکھیں گے، انہیں بات بات پر جھڑکیں گے، وہ روئیں گے تو انہیں چپ کرانے کی کوشش نہیں کریں گے.انہیں ضرورتیں پیش آئیں گی تو وہ ان کو پورا نہیں کریں گے.یہ خیالات جب کسی شخص کے دل اور دماغ پر حاوی ہوتے ہیں تو اس کے جسم پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، اس کا بدن کپکپا جاتا ہے اور وہ جان دینے سے گھبرا تا ہے اور اس میدان سے بچنے کی کوشش کرتا ہے.اسی طرح مالی قربانی کا وقت آئے تو وہ گھبرا جاتا ہے اور اسے اپنے بچوں کی پرورش کا خیال روپیہ کو بلادریغ خرچ کرنے نہیں دیتا.اپنی زندگی تک تو اسے پروا نہیں ہوتی، سمجھتا ہے جس طرح بھی ہو گا میں اپنے بچوں کی پرورش کر لوں گا.لیکن ساتھ ہی اس کے دل میں یہ خیال بھی آ جاتا ہے کہ اگر مال لٹانے کے بعد میں مر گیا اور میرے بچوں کے لئے کوئی چیز باقی نہ رہی تو ان کا بعد میں کیا حال ہو گا.اس وقت اگر وہ سمجھتا ہے کہ قوم نے میرے بچوں کی پرورش نہیں کرنی تو وہ بزدل بن جاتا ہے اور قربانی کے لئے تیار نہیں ہوتا.حقیقت یہ ہے کہ سب سے زیادہ ڈر انسان کو اپنی موت کا نہیں ہوتا بلکہ سب سے زیادہ ڈر اسے اس بات کا ہوتا ہے کہ میری موت کے بعد میرے بچوں کا کیا حال ہو گا.یہ ایک جذباتی سوال ہے جو اس کے اندر ایک کشمکش اور ہیجان پیدا کر دیتا ہے.اس کے ارادوں میں تعطّل اور اس کی خواہشات میں جمود کی کیفیت رونما ہو جاتی ہے.وہ دیکھتا ہے کہ قوم کے کئی بچے یتیم ہیں مگر ان کی حالت یہ ہے کہ وہ لوگوں کے دروازوں پر جا جا کر اپنے لئے آٹا مانگتے پھرتے ہیں یہ دیکھ کر وہ سمجھتا ہے اگر میں مر گیا تو میرا بچہ بھی کل اسی طرح بھیک مانگنے پر مجبور ہو گا.پھر وہ ایک اور نظارہ دیکھتا ہے تو اس کا قلب اور بھی سہم جاتا ہے.وہ دیکھتا ہے کہ چند یتیم آٹا مانگنے کے لئے کسی کے دروازہ پر آئے انہوں نے دستک دی اور کہا ہمیں آٹا دیا جائے.گھر والا ان کی آواز کو سنتا ہے تو بڑ بڑا کر کہنے لگ جاتا ہے ان لوگوں نے تو ہمارے کان کھا لئے ہیں.روز آٹا روز آٹا.وہ یہ فقرہ سنتا ہے تو اس میں اور زیادہ بزدلی پیدا ہو جاتی ہے.وہ کہتا ہے اگر میں مر گیا تو میرا بچہ اوّل تو بھیک مانگنے پر مجبور ہو گا اور پھر لوگوں کا سلوک اس سے یہ ہو گا کہ وہ تو آٹا مانگے گا اور لوگ اسے کہیں گے تو نے ہمارے کان کھا لئے.پھر وہ دیکھتا ہے کہ فلاں شخص مر گیا ہے تو اس کے یتیم بچے آج فلاں گھر میں برتن مانجھ مانجھ کر گذارہ کر رہے ہیں.وہ اپنی نظر کو وسیع کرتا اور اپنی قوت فکریہ پر زور ڈالتا ہے.تو کہتا ہے جب میں مر جاؤں گا میرے بچوں سے بھی اسی قسم کا کام لیا جائے گا.اس پر اس کی بزدلی کا پارہ اور زیادہ اوپر چڑھ جاتا ہے بلکہ اگر کوئی خود ہی یتیم پر ظلم کر رہا ہو تو بھی اس میں بزدلی آجاتی ہے اور وہ سمجھتا ہے جو سلوک آج میں دوسروں کے یتیم بچوں سے کر رہا ہوں وہی سلوک میرے مرنے کے بعد لوگ میرے بچوں
Page 277
کے ساتھ کریں گے.پس یاد رکھو یتیم کی خبر گیری کرنا صرف نیکی اور تقویٰ ہی نہیں بلکہ قوم کے کیرکٹر کو بلند کرنا اور اسے قربانیوں پر زیادہ سے زیادہ دلیر بنانا ہے.جو قوم یتامٰی سے حسن سلوک نہیں کرتی وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی.میں نے ایک دفعہ گھر میں نصیحت کی کہ یتامٰی سے ایسا ہی سلوک کرنا چاہیے جیسے اپنے بچوں سے کیا جاتا ہے.اگر اس رنگ میں ان سے سلوک نہیں کیا جاتا تو قطعی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ تم نے کسی یتیم کی پرورش کی ہے میں نے کہا میں بعض یتامیٰ کا خرچ خود دیتا ہوں مگر پھر بھی میری بعض بیویاں ان سے اس طرح کام لیتی ہیں جس طرح نوکروں سے کام لیا جاتا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ ان سے بالکل کام نہ لیا جائے اگر ان سے کام نہیں لیا جائے گا تو وہ آوارہ ہو جائیں گے میںصرف یہ کہتا ہوں کہ ان سے ایسا ہی کام لیا جائے جو اپنے بچوں سے بھی لے لیا جاتا ہے اور اگر کوئی کام ایسا ہو جو ہم اپنے بچوں سے کروانے کے لئے تیار نہ ہوں تو ہمیں وہ کام کسی یتیم سے بھی نہیں لینا چاہیے.بہرحال میں نے گھر میں نصیحت کی کہ روپیہ تو میں دے دیتا ہوں مگر کام کی ذمہ واری تم پر ہے تمہیں چاہیے کہ ایسے رنگ میں ان سے کام مت لو گویا وہ تمہارے نوکر ہیں.میری اس نصیحت کے بعد اُمّ طاہر مرحومہؓ نے ایک یتیم بچہ پالا بعد میں تو اس کی حالت ایسی اچھی ثابت نہیں ہوئی مگر بہرحال انہوں نے اس بچے کو اسی طرح پالا جس طرح وہ اپنے بچوں کو پالتی تھیں اور انہوں نے کسی قسم کا فرق پیدا نہ ہونے دیا.اس بارہ میں نہایت ہی اعلیٰ نمونہ عزیزم مرزا ظفر احمد نے دکھایا ہے جو میرے بھتیجے ہیں.بنگال کے وہ فاقہ زدہ لوگ جو لاکھوں کی تعداد میں وہاں ہلاک ہوئے ہیں ان میں سے ایک کی یتیم بچی لے کر انہوں نے اس کی پرورش شروع کی ہے اور اس عمدگی اور خوبی کے ساتھ وہ اس کی پرورش کر رہے ہیں کہ اس میں اور ان کی اپنی لڑکی میں کوئی بھی فرق نظر نہیں آتا.وہ اس کو مار پیٹ لیتی ہے اور یہ اس کو مار پیٹ لیتی ہے، دونوں کے بالکل ایک جیسے کپڑے ہوتے ہیں، ایک جیسا دونوں کو کھانا کھلاتے ہیں، ایک جیسی دونوں کو تعلیم دلاتے ہیں، اور ایک جیسی دونوں کی نگرانی رکھتے ہیں ان کی لڑکی اس لڑکی کو باجی کہتی اور اس کا احترام کرتی ہے اور یہی وہ چیز ہے جسے یتیم کا پالنا کہتے ہیں.یتیم کا پالنا یہ نہیں کہ کسی کو گھر میں نوکر کے طور پر رکھ لیا، سارا دن اس سے کام لیتے رہے، کھانے کو اسے روکھی سوکھی روٹی دے دی ، پہننے کے لئے پھٹا پرانا کپڑا دے دیا، ذرا غلطی ہوئی تو گالیاں دینے لگ گئے یا تھپڑوں سے اس کی مرمت شروع کر دی اور پھر یہ خیال کر لیا کہ ہم یتیم کی پرورش کر رہے ہیں اسے اسلامی اصطلاح میں قطعاً یتیم پروری نہیں کہا جاتا.یتیم پروری یہ ہے کہ انسان اپنے بچوں کی طرح دوسرے کے یتیم بچہ کو رکھے اور اپنے سلوک میں ذرا بھی فرق نہ آنے دے.محض کسی کو روٹی کھلا دینا اور بات ہے اور یتیم پروری اور
Page 278
چیز ہے.قرآن کریم نے جو کچھ کہا ہے وہ یہ ہے کہ كَلَّا بَلْ لَّا تُكْرِمُوْنَ الْيَتِيْمَ اے لوگو! تم یتیم کا اکرام نہیں کرتے تھے یہ نہیں کہاکہ لَا تُطْعِمُوْنَ الْیَتِیْمَ اے لوگو! تم یتیم کو کھا نا نہیں کھلاتے تھے اگر محض کھانے کا ذکر ہوتا تو یہاں اکرام کا لفظ نہ ہوتا بلکہ اِطْعَام کا لفظ ہوتا.اکرام کا لفظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رکھا جانا صاف بتا رہا ہے کہ الٰہی منشا یہ ہے کہ یتیموں کی ایسے رنگ میں پرورش کی جائے کہ ان کا احترام مدنظر ہو یہ نہ ہو کہ صدقہ کے طور پران کو روٹی دی جا رہی ہو.میں نے قادیان میں ایک دفعہ یتیم خانہ بنایا تو تھوڑے دنوں کے بعد ہی مجھے پتہ لگا کہ ان یتیموں سے سارا سارا دن کام لیا جاتا ہے.کام لینا منع نہیں لیکن ہمیں ان سے اتنا ہی کام لینا چاہیے جتنا ہم اپنے بیٹے سے کام لیتے ہیں یہ نہ ہو کہ ہمارا بیٹا تو آرام سے بیٹھا رہے اور کام کا بوجھ یتیم پر ڈال دیا جائے محض اس لئے کہ اس کا باپ زندہ نہیں اس کی ماں زندہ نہیں اور وہ اب دوسرے لوگوں کے رحم پر ہے.اسے بیٹوں کی طرح رکھا جائے، بیٹوں کی طرح اس سے کام لیا جائے اور پھر اگر اس میں اور اپنے بیٹوں میں کبھی لڑائی ہو جائے تو بے شک یہ اس کو مارپیٹ لیں اور وہ ان کو مارپیٹ لے اس وقت ماں اسے یہ نہ کہے کہ خبردار میرے بیٹے پر ہاتھ اٹھا یا تو تجھے مار مار کر سیدھا کر دوں گی.اگر اس طرح کسی یتیم کو رکھا جائے تو بے شک کسی غلطی پر اسے مار بھی لیا جائے اس میں کوئی حرج نہیں آخر ہم اپنے بچے کو بھی بعض دفعہ مار لیتے ہیں.پھر اگر کسی یتیم کو اس کی کسی غلطی پر بالکل اسی طرح جس طرح ہم اپنے بچوں کی اصلاح کے لئے انہیں مارتے ہیں اگر کبھی مار لیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں مگر بہرحال اس کی عزت نظر انداز نہیں ہونی چاہیے.قرآن کریم صرف یتامیٰ کو کھانا کھلانا ضروری نہیں سمجھتا بلکہ فرماتا ہے قومی ترقی کے لئے یہ نہایت ضروری امر ہے کہ یتیم کو عزت سے رکھا جائے اگر یتامیٰ کا اکرام قوم میں نہیں پایا جاتا تو خواہ تم ہزاربار لوگوں سے کہو کہ جاؤ اور خدا کی راہ میں مر جاؤ.جاؤ اور اپنی جانیں قربان کر دو.وہ کہیں گے ہم چلے تو جائیں مگر ایسا نہ ہو کہ ہم مر جائیں اور ہمارے بچوں کو تکلیف اٹھانی پڑے لیکن اگر وہ یہ دیکھیں کہ ہماری زندگی اور ہماری موت بچوں کی پرورش کے لحاظ سے برابر ہے ہمارے مرنے کے بعد بھی یہ اسی طرح رہیں گے بلکہ موجودہ حالت سے بھی ہزار گنا بڑھ کر ان کی پرورش کے سامان ہوں گے تو بے شک تم قوم کے ایک ایک فرد کو کٹواتے جاؤ، ایک ایک فرد کو مرواتے جاؤ کوئی ایک شخص بھی اپنے قدم کو پیچھے نہیں ہٹائے گا اور خوشی سے اپنے آپ کو قربانی کے لئے پیش کر دےگا.غرض یہ ایک نہایت ہی عظیم الشان مسئلہ ہے اور جب تک کسی قوم کے افراد اس کو پوری طرح نہ سمجھ لیں وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتے.
Page 279
دوسری بات خدا تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ وَ لَا تَحٰٓضُّوْنَ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ تم آپس میں ایک دوسرے کو رغبت نہیں دلاتے کہ غریب آدمی کو کھانا کھلایا جائے.اگر غرباء کی خبر گیری نہ ہو تو قومی جنگوں میں کبھی کا میابی نہیں ہوتی اور سپاہی بہت کم ملتے ہیں کیونکہ دنیا میں غرباء زیادہ ہوتے ہیں اگر سپاہیوں اور لڑنے والوں کے ذہن میں یہ ہو کہ ہماری قوم ہماری محسن ہے.ہم بیمار ہوئے تو اس نے ہمارا علاج کیا.ہمارے پاس کپڑے نہ تھے تو اس نے ہمارے لئے کپڑے مہیا کئے.ہم بھوکے تھے تو اس نے ہمارے لئے غلہ مہیا کیا.ہم حاجت مند تھے تو اس نے ہماری حاجات کو پورا کیا.تو گو کمینے اور رذیل لوگ بھی ہرقوم میں پائے جاتے ہیں مگر بہرحال جو شریف ہوں گے اور یہی طبقہ زیادہ ہوتا ہے وہ کہیں گے جب قوم نے ہمارے ساتھ یہ احسان کیا ہے وہ احسان کیا ہے تو آج ہم قومی ضرورت کے وقت کیوں پیچھے ہٹیں ہم آگے بڑھیں گے اور قوم کے لئے اپنی جانوں کو قربان کر دیں گے.لیکن اگر وہ یہ سمجھتے ہوں کہ ہم بھوکے مرتے رہے مگر ہمیں کسی نے نہ پوچھا، ہم ننگے پھرتے رہے مگر کسی نے ہمارا ننگ نہ ڈھانکا، ہم بیمار ہوئے مگر کسی نے ہمارا علاج نہ کیا، ہم محتاج ہوئے مگر کسی نے ہماری احتیاج کو رفع نہ کیا.تو وہ کہیں گے ہمارے لئے قوم نے کیا کیا تھا کہ آج ہم اس کے لئے قربانی کریں.وہ ہم سے بے اعتنائی کرتی رہی ہے آج ہم اس سے بے اعتنائی کریں گے.پس غرباء کی خبر نہ کرنے کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ قربانی کا مادہ لوگوں کے دلوںمیں سے کم ہو جاتا ہے اور قومی جنگوں میں کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی.میں نے قادیان میں دیکھا ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ غرباء کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو.ہم ان کے لئے کپڑے مہیا کرتے ہیں، ان کے لئے غلہ کا انتظام کرتے ہیں، ان کی روپیہ سے امداد کرتے ہیں، ان کو طبّی امداد بہم پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اور حتی الامکان ان کی تکالیف کو زیادہ سے زیادہ کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں.اس کے بعد بھی گو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو باوجود اس سارے انتظام کے جماعت پر اعتراض کرتے رہتے ہیں.وہ سمجھتے ہیں لوگوں کا کام صرف یہی ہے کہ ان پر روپیہ خرچ کرتے چلے جائیں ان پر کوئی ذمہ واری نہیں.لیکن پھر بھی اکثریت ایسی ہے جو محسوس کرتی ہے کہ یہ جماعت ہمارے لئے قربانی کر رہی ہے اس لئے قومی ضرورتوں کے وقت ہمیں بھی دوسروں سے زیادہ قربانی کرنی چاہیے.چنانچہ وہ لوگ خود بھوکے ہوتے ہیں مگر جب کسی چندہ کی تحریک ہو مزدوری کر کے بھی اس میں ضرور حصہ لیتے ہیں اور گو وہ اس تحریک کے مخاطب نہیں ہوتے اور ان پر کسی قسم کی ذمہ واری بھی نہیں ہوتی مگر چونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ قوم ہمارے لئے قربانی کرتی ہے اور وہ ہماری ضروریات کا خیال رکھتی ہے اس لئے وہ بھی قربانی کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ قومی تحریکات میں حصہ دار بن جائیں.پس غرباء کی خبر گیری کا سب سے بڑا فائدہ
Page 280
یہ ہے کہ اگر قومی جنگ ہو جائے تو چونکہ قوم کی اکثریت غرباء پر مشتمل ہوتی ہے اس لئے قوم کو کثرت سے کام کرنے والے مل جاتے ہیں.ایک کروڑ پتی کی تلوار صرف ایک تلوار کا کام دے سکتی ہے لیکن جنگوںمیں ایک تلوار نہیں کروڑوں تلواروں کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ کروڑوں تلواریں اس وقت تک مہیا نہیں ہو سکتیں جب تک کروڑوں غرباء کے حقوق کا خیال نہ رکھا جائے اور ان کو پوری طرح مطمئن نہ کیا جائے.اگر مساکین کے کھانے پینے کا خیال رکھا جائے تو یہ لازمی بات ہے کہ جب قوم پر کوئی مصیبت آئے گی شریف الطبع لوگوں میں یہ احساس پیدا ہو گا کہ قوم نے ہم پر احسان کیا تھا اب اس پر مصیبت آئی ہے تو ہم اس کی مدد کریں.جیسے انگلستان، امریکہ، روس اور جرمنی وغیرہ ممالک میں موجودہ جنگ میں لاکھوں آدمی کام آئے اور انہوں نے اپنے آپ کو قوم کے لئے قربان کر دیا.اس کی وجہ درحقیقت یہی ہے کہ ان قوموں میں غرباء کی پرورش کا احساس بہت زیادہ پایا جاتا ہے ہندوستا ن میں جو لوگ فوجی بنتے ہیں وہ یا تو اس لئے فوج میں بھرتی ہوتے ہیں کہ ان کے باپ دادا فوج میں کام کرچکے ہوتے ہیں اور یا پھر اس لئے جاتے ہیں کہ ان کو بعد میں مربعے مل جائیں.قومی احساس ہندوستانیوں میں بہت کم ہوتا ہے.پھر اگر غرباء کے کھانے پینے کا خیال رکھا جائے تو ان کے دلوں میں یہ احساس رہتا ہے کہ جو لوگ اپنے اموال میں ہماری ضروریات کا خیال رکھتے ہیں وہ فتوحا ت میں بھی ہمارا ضرورخیال رکھیں گے اور یہ بھی قوم کی ترقی کا ایک ذریعہ ہوتا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ قومی اموال کی ترقی صرف امراء کو ہی نہیں بلکہ ہمیں بھی فائدہ پہنچائے گی.جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اموال میں غرباء کے حقوق اس لئے بیان کئے ہیں كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةًۢ بَيْنَ الْاَغْنِيَآءِ مِنْكُمْ(الـحشـر:۸)تا کہ تم روپیہ کو اس طرح استعمال نہ کرو کہ وہ دولت مندوں میں ہی چکر لگانے لگے بلکہ غرباء کو بھی روپیہ ملے.پس غرباء کی خبر گیری کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں جتنی قوم ترقی کرے گی اتنا ہی ہمارا حصہ بڑھتا چلا جائے گا لیکن اگر ان کو حصہ نہ دیا جائے تو وہ کہتے ہیں ہمیں تو حصہ ملنا نہیں قومی اموال کی ترقی امراء کو ہی فائدہ دے گی اس لئے ہم اپنی جانوں کو کیوں ضائع کریں.تیسری چیز جس کا ان آیات میں ذکر کیا گیا ہے وہ اَ کْلِ تُرَاث ہے جو اسراف کے نتیجہ میں پیدا ہوتا ہے.جب کسی قوم میں اسراف پیدا ہوجائے تو وہ بھی یقینی طور پر تباہ و برباد ہوجاتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَاْکُلُوْنَ التُّرَاثَ اَکْلًا لَّمًّا کہ تمہیں باپ دادا سے مال ملا مگر بجائے اس کے کہ تم اسے ترقی دیتے اور اسے بڑھانے کی کوشش کرتے تم نے اسے تباہ کرنا شروع کر دیا.غرض اسراف بھی قومی تنزل کی ایک بہت بڑی علامت ہے اور اس کے دو بڑے نقصان ہوتے ہیں.اوّل یہ کہ انسان میں نکما پن پیدا ہو جاتا ہے.باپ دادا کی طرح اگر وہ کام
Page 281
کرتا تو نکما پن اس میں پیدا نہ ہوتا مگر وہ محنت کو صرف روٹی کمانے کا ایک ذریعہ سمجھ لیتا ہے اور جب اسے باپ دادا کی جائیداد پر قبضہ کر لینے کی وجہ سے روٹی مل جاتی ہے تو وہ کوئی کام نہیں کرتا.جس قوم میں ایسے آدمی پیدا ہو جائیں کہ وہ کوئی کام نہ کریں وہ اس جونک کی طرح ہوتے ہیں جو جسم کا خون چوس لیتی ہے اور اس قابل ہوتے ہیں کہ ان کی زیادہ سے زیادہ مذمت کی جائے.اگر کسی قوم میں ہزاروں لوگ بھی کروڑ پتی ہوں لیکن وہ سب کے سب کام کر رہے ہوں اور ان میں سے ایک شخص بھی ایسا نہ ہو جس کے اندر نکما پن پایا جاتا ہو تو وہ قوم کبھی تباہ نہیں ہوتی.لیکن اگر ایک کروڑ پتی بھی ایسا ہے جو باپ دادا کی جائیداد لے کر بیٹھ گیا ہے اور سمجھتا ہے کہ اب مجھے کسی کام یا کسی محنت کی ضرورت نہیں محنت تو اس لئے کی جاتی ہے کہ روٹی ملے میرے پاس روٹی کا کافی سامان ہے میں کیوں محنت کروں تو اس قوم کی تباہی کی بنیادی اینٹ وہ شخص اپنے ہاتھ سے رکھنے والا ہوتا ہے.پس محض کسی کروڑپتی کا قوم میں پایا جانا اس کی بربادی کی علامت نہیں کیونکہ گو وہ کروڑپتی ہو گا مگر نکما نہیں ہو گا بلکہ کام کر رہا ہو گا.نکما وہ ہے جو کہتا ہے کہ باپ کا ایک کروڑ روپیہ میرے پاس ہے مجھے اب محنت کی ضرورت نہیں.مجھے اب کام کی ضرورت نہیں میرے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ باپ کے روپیہ پر تصرّف رکھوں اور جس طرح جی میں آئے کروں.یوں تو انگلستان میں بھی کروڑ پتی پائے جاتے ہیں مگر وہ لوگ ایسے ہیں کہ باوجود کروڑ پتی ہونے کے محنت کرتے ہیں اور اپنے روپیہ کو برباد کرنے کی بجائے اس سے کوئی نہ کوئی کارخانہ جاری کر دیتے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پچاس، سو، دو سو یا ہزار دو ہزار آدمیوں کو مزدوری مل جاتی ہے اور وہ روپیہ قوم کی ترقی کے کام آتا رہتا ہے.بے شک وہاں بھی بعض ایسے لوگ ہیں جو بنکوں میں اپنا روپیہ جمع کر دیتے ہیں مگر زیادہ تر ایسے ہی لوگ ہیں جو اپنے روپیہ سے کارخانے جاری کر دیتے ہیں یا بنکوں میں روپیہ جمع کر کے خود کسی سوسائٹی کے پریذیڈنٹ یا سیکرٹری بن جاتے ہیں اور اس طرح آنریری طور پر قومی خدمات سرانجام دیتے ہیں اس لئے وہ قوم تباہ نہیں ہوتی.اس جگہ ایسے لوگوں کا ذکر نہیں بلکہ نکمے امراء کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ تمہارا کام یہ ہے کہ تم اپنے باپ دادا کے روپیہ کو کھاتے رہتے ہو اور خود ساری عمر نکماپن میں گذار دیتے ہو جس قوم میں ایسے منحوس لوگ پیدا ہو جائیں وہ قوم کبھی ترقی نہیں کرسکتی.دوسرے خواہ تم اچھا کہو یا برا.یہ ایک حقیقت ہے کہ جو لوگ زیادہ ہوشیار ہوتے ہیں وہ قوم میں ضرور عزت حاصل کر لیتے ہیں اور اس وجہ سے ان سے اتر کر ان کی اولاد کو بھی کچھ نہ کچھ عزت قوم میں حاصل ہو جاتی ہے خواہ دنیا میں کتنی بغاوت ہو جائے، لوگ بالشوزم کے قائل ہو جائیں پھر بھی یہ بات کبھی مٹ نہیں سکتی کہ جب کوئی شخص قوم میں کوئی خاص اعزاز حاصل کر لیتا ہے تو کچھ نہ کچھ عزت اس کی اولاد کو بھی مل جاتی ہے.یہ ایک فطرتی چیز ہے
Page 282
جس کو کوئی شخص بدل نہیں سکتا جس نے کوئی نمایاں کام کیا ہوتا ہے اس کی اولاد خواہ مستحق ہو یا نہ ہو مگر بہرحال اس عزت کا کچھ نہ کچھ حصہ اولاد کو بھی حاصل ہو جاتا ہے.اب یہ لازمی بات ہے کہ جب ایسے لوگوںمیں سستی پیدا ہوجائے گی تو چونکہ بڑے خاندان ہی لیڈر ہوتے ہیں ان کی سستی کا قوم پر یہ اثر پڑے گا کہ اس کا شیرازہ منتشر ہوجائے گا جب وہ لوگ جنہیں قوم میں عزت حاصل ہو جن کے ہاتھ میں لیڈری کی باگ ڈور ہو، باپ دادا کی جائیداد پر بیٹھے روٹیاں توڑ رہے ہوں تو یہ قدرتی بات ہے کہ اس قوم میں لیڈر کم ہو جائیں گے.بے شک کچھ نئے لیڈر بھی بن جاتے ہیں مگر کچھ باپ دادا کی عزت اور خاندانی وجاہت کی وجہ سے لیڈر سمجھے جاتے ہیں اگر ان میں اس قسم کی سستی پیدا ہو جائے تو ایک قسم کے لیڈر ہی رہ جائیں گے دوسری قسم کے لیڈر نہیں رہیں گے اور اس طرح قوم کے راہنما محدود ہو جائیں گے.چوتھی چیز محبت مال ہے.مال کی محبت حلال وحرام کا امتیاز اڑا کر انسان کو ظلم کی طرف مائل کر دیتی ہے.جس شخص کے دل میں انتہائی طور پر مال کی محبت ہو گی وہ حلال اور حرام میں کوئی امتیاز نہیں کرے گا.حلال ذریعہ سے مال آئے گا تو اسے بھی لے لے گا، حرام ذریعہ سے مال آئے گا تو اسے بھی لے لے گا اور جس شخص میں حلال وحرام کا امتیاز نہ رہے وہ ظلم پر آمادہ ہو جاتا ہے اور جس قوم میں ظالم پیدا ہو جائیں اس کا شیرازہ کبھی متحد نہیں رہ سکتا.یہ ایک لازمی اور طبعی بات ہے کہ جب انتہائی طور پر مال کی محبت پیدا ہو گی حلال و حرام کی تمیز جاتی رہے گی اور جب حلال و حرام کی تمیز نہ رہے گی تو انسان ظلم سے بھی دریغ نہیں کرے گا اور جب قوم میں ایسے لوگ پیدا ہو جائیں جن کو دوسروں کو لوٹنے میں مزا آتا ہو تو وہ قوم کبھی پنپ نہیں سکتی.دوسرے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ قوم صنعتی ترقی سے محروم رہ جاتی ہے جس شخص کے دل میں مال کی شدید محبت ہو وہ بعض دفعہ روپیہ کو کام پر لگانے سے ڈرتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ شاید تجارت یا صنعت میں نقصان نہ ہو جائے بہتر یہی ہے کہ میں اس کو اپنے پاس محفوظ رکھوں.نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا مال بھی نہیں بڑھتا اور غرباء کے حقوق کا بھی اتلاف ہوتا ہے.فرض کرو دس ہزار روپیہ سے یہ ایک کارخانہ جاری کرتا اور بیس پچیس مزدور اس کارخانہ میں کام کرنے والا ہوتا تو بیس پچیس خاندان اس کے روپیہ سے پرورش پانے لگ جاتے.آگے ایک خاندان میں اگر پانچ پانچ آدمی بھی فرض کر لئے جائیں تو اس کے معنے یہ بنتے ہیں کہ اس نے دس ہزار روپیہ خرچ کر کے سَو سوا سَو لوگوں کے لئے مزدوری مہیا کی.لیکن اگر وہ روپیہ خزانہ میں بند کر دیتا ہے تو سَو سوا سَو آدمیوں کی روٹی ماری جاتی ہے.اسی طرح اگر قوم میں دس ہزار مالدار ہوں اور وہ اپنے روپیہ کو خزانہ میں محفوظ رکھیں تو لاکھوں لوگوں کی
Page 283
مزدوری ماری جائے گی اور صنعتی لحاظ سے قوم کو شدید نقصان پہنچے گا.پس دوسرا نقصان مال کی محبت کا یہ ہے کہ قوم صنعتی لحاظ سے ترقی سے محروم رہ جاتی ہے.تیسرا نقصان یہ ہے کہ حُبِّ مال کی وجہ سے قومی چندوں میں کمی آ جاتی ہے.جب بھی کوئی تحریک ہو مال کی محبت غالب آ جاتی ہے اور قومی تحریکات میں حصہ لینے کے لئے انسان تیار نہیں ہوتا.چوتھے اس کا یہ بھی نتیجہ ہوتا ہے کہ جن کے دلوں (میں) مال کی محبت ہوتی ہے وہ قومی ایثار کے وقت دشمن کے غلبہ سے ڈر کر غدار بن جاتے ہیں.قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتِلْکَ الْاَیَّامُ نُدَاوِلُھَا بَیْنَ النَّاسِ (اٰل عمران:۱۴۱) لڑائی میں کبھی ایک کا پلّہ بھاری ہو جاتا ہے اور کبھی دوسرے کا.اونچ نیچ ضرور ہوتی رہتی ہے ایسی حالت میں وہ شخص جس کے دل میں مال کی محبت ہوتی ہے اگر اسے ذرا بھی یہ پتہ لگے کہ دشمن غالب آنے والا ہے تو وہ چوری چھپے دشمن کے ساتھ ساز باز شروع کر دیتا ہے اور اپنی قوم سے غدّاری کرتا ہے محض اس لئے کہ اس کا مال محفوظ رہے.حضرت خلیفہ اوّل رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ انگریز سود لے کر بھی لوٹتے ہیں اور سود دے کر بھی لوٹتے ہیں پھر اس کے متعلق ایک واقعہ سنایا کرتے تھے.آپ فرماتے اودھ کی اسلامی حکومت اس طرح تباہ ہوئی کہ پہلے انگریزوں نے لوگوں میں یہ تحریک شروع کر دی کہ اگر تم ہمارے بنک میں اپنا روپیہ جمع کرو تو تمہیں اڑھائی فیصدی نفع دیا جائے گا.یہ لالچ اتنا بڑا تھا کہ لوگوں نے اپنا تمام روپیہ کلکتہ کے انگریزی بنک میں جمع کرا دیا.عورتوں نے اپنے زیورات تک بیچ ڈالے اور روپیہ انگریزوں کے حوالے کر دیاکیونکہ انہیں آئندہ کے متعلق بڑی بڑی امیدیں دلائی گئی تھیں.انہیں کہا گیا تھا کہ اگر تمہارا دس لاکھ روپیہ جمع ہوا تو تمہیں پچیس ہزار روپیہ سود دیا جائے گااور پھر تمارا اصل مال بھی بالکل محفوظ رہے گا جب تم مانگو گے روپیہ واپس دے دیا جائے گا.نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کا سارے کا سارا روپیہ کلکتہ کے انگریزی بنک میں جمع ہو گیا اس کے بعد انگریزی فوج نے حملہ کر دیا.لکھنؤ جو اودھ کی حکومت کا دارالسلطنت تھا وہاں کے بڑے بڑے سرداروں سے انگریزوں نے کہہ دیا کہ خبردار! تم میں سے کوئی شخص بادشاہ کو یہ خبر نہ پہنچائے کہ انگریزی فوج حملہ کے لئے آ رہی ہے اگر تم نے ایسا کیا تو تمہارا جو روپیہ بنک میں جمع ہے وہ ضبط ہو جائے گا.ان غدار افسروں نے ایسا ہی کیا.بادشاہ مرغ لڑوا رہا تھا اور کنچنیوں کے ناچ گانے میں مشغول تھا کہ ایک شخص بول اٹھا اور کہنے لگا کہ حضور سنا ہے انگریزی فوج آ رہی ہے وہ افسر جو اندرونی طور پر انگریزوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے انہوں نے اس کو ڈانٹنا شروع کر دیا اور بادشاہ سے کہا حضور کے اقبال کے سامنے انگریزوں کی کیا مجال ہو سکتی ہے یہ ایک بے وقوف شخص یوں ہی بول پڑا ہے.یہ حضور کے
Page 284
آرام اور مزے کا وقت تھا مگر اس نے سارا مزہ خراب کر دیا انگریزوں کی کیا مجال ہے کہ وہ حضور کی شاہی کو کوئی نقصان پہنچا سکیں.غرض بادشاہ کو انہوں نے ناچ گانوں اور مرغوں کے لڑوانے میں ہی مشغول رکھا اور انگریزی فوج لکھنؤکے اندر داخل ہو گئی الغرض محبت مال قوم میں غدّاری پیدا کر دیتی ہے اس لئے اگر کوئی قوم ترقی کرنا چاہے تو اسے اپنے افراد کے قلوب میں سے مال کی محبت کو مٹا دینا چاہیے اس کے بغیر وہ حقیقی اور پائیدار ترقی حاصل نہیں کر سکتی.چونکہ یہاں کفار کا ذکر تھا اور انہیں یہ بتایا جا رہا تھا کہ تم تباہ ہو جاؤ گے اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں یہ مضمون بیان کیا کہ تمہاری تباہی کے سامان کہیں باہر سے نہیں آئیں گے بلکہ تمہارے اندر ہی تمہاری بربادی کے سامان موجود ہیں.لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم کی قوم کا ہر فرد جانتا ہے کہ اگر میں لڑائی میں مارا گیا تو مجھ سے بڑھ کر شفیق باپ میرے بچوں کے لئے موجود ہے.مسکین جانتا ہے کہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم کو طاقت ملی تو مجھے کھانا ملے گا، مجھے کپڑا ملے گا، مجھے بیماری کے وقت علاج میسر آئے گا اور مجھے فتوحات میں برابر کا حصہ ملے گا.باپ دادا سے ورثہ حاصل کرنے والا جانتا ہے کہ میں نے اپنے مال کو تلف نہیں کرنا بلکہ اسے قومی کاموں پر صرف کرنا اور اسے پہلے سے بھی زیادہ بڑھانا ہے تاکہ قوم کا قدم ترقی کی طرف بڑھے تنزل کی طرف نہ جھکے.اور اگر کسی کے پاس مال ہے تو وہ اس سے محبت نہیں رکھتا.چندے کے وقت سارے کا سارا مال لے آتا ہے اور پھر اس بات کی احتیاط رکھتا ہے کہ اس کے مال میں کوئی حرام پیسہ نہ آ جائے جب ترقی کی تمام علامات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں میں پائی جاتی ہیں اور تنزل کی تمام علامات تم میں موجود ہیں تو تم یہ خیال ہی کس طرح کر سکتے ہو کہ تم غالب آ جاؤ گے اور مسلمان مغلوب ہو جائیں گے.بے شک تعداد کے لحاظ سے تم زیادہ ہو مگر بہت سی چڑیاں باز پر فتح حاصل نہیں کر سکتیں.تم میں سے ہر شخص وہ ہے جو یتامٰی کی خبرگیری نہیں کرتا اور اس لئے وہ انتہائی طور پر بزدل اور ڈرپوک ہے.تم میں سے ہر شخص وہ ہے جو غرباء کی اعانت نہیں کرتا اس لئے تمہیں قومی جنگوں کے وقت کبھی کامیابی نہیں ہو سکتی.تم میں سے ہر شخص وہ ہے جسے اپنے باپ دادا سے جب ورثہ میں روپیہ ملتا ہے تو وہ اسے عیاشی میں برباد کر دیتا ہے.تم میںسے ہر شخص وہ ہے جس کے دل میں مال کی انتہائی محبت پائی جاتی ہے اور اس وجہ سے جب قوم کے لئے مال کی ضرورت ہو تم میں سے کوئی شخص روپیہ خرچ کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتا.جب تمہاری یہ حالت ہے اور مسلمانوں کی وہ حالت تو یہ لازمی بات ہے کہ مسلمان جیتیں گے اور تم ہارو گے.یہی چیز ہے جو ہماری جماعت کے افراد کو اپنے مدنظر رکھنی چاہیے.اگر ہماری جماعت ترقی کرنا چاہتی ہے تو
Page 285
ضروری ہے کہ وہ یہ چار باتیں اپنے اندر پیدا کرلے اور پوری مضبوطی کے ساتھ ان پر قائم رہے.اگر ہمارے مبلّغ اور ہمارے معلّم اور ہمارے صدر اس بات کو مدنظر رکھیں کہ ہم نے یتامیٰ کی خبر گیری کرنی ہے ہم نے ان کو صرف کھانا ہی نہیں کھلانا بلکہ ان کا اکرام کرنا ہے، اگر وہ سمجھیں کہ ہم نے مساکین کو کھانے پینے کے لحاظ سے ہر قسم کی تکالیف سے محفوظ رکھنا ہے، اگر وہ خیال رکھیں کہ ہم نے لوگوں میں کام کرنے کی عادت پیدا کرنی ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم میں سے کوئی شخص اپنے باپ دادا کی جائیداد لے کر بیٹھ جائے اور خود کوئی کام نہ کرے اگر ایک شخص کروڑ پتی بھی ہے مگر وہ صرف اپنے باپ دادا کی جائیداد پر بیٹھا ہوا ہے خود کوئی کام نہیں کرتا تو قوم کو اس کی ذرا بھی عزت نہیں کرنی چاہیے اس کے متعلق یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وہ بڑا رئیس ہے بلکہ اسے چوہڑوں اور چماروں سے بھی زیادہ ذلیل اور بد ترسمجھنا چاہیے.اسی طرح اگر قوم میں کوئی شخص ایسا ہو جو مال سے محبت رکھتا ہو تو جماعت کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ وہ شخص ہے جو کسی وقت ہمارے لئے غدّار ثابت ہو گا اور جب بھی اسے موقع ملے گا روپیہ کے ڈر کے مارے دشمن سے مل جائے گا.اگر یہ چار باتیں تم اپنے اندر پیدا کر لو تو چاہے تمہارے دشمن لاکھ ہوں، کروڑ ہوں، دس کروڑ ہوں وہ کروڑیا دس کروڑ چڑیاں ہوں گی اور تم ان کے مقابلہ میں باز ہو گے.كَلَّاۤ اِذَا دُكَّتِ الْاَرْضُ دَكًّا دَكًّاۙ۰۰۲۲ خبردار! جب زمین ہلا کر ہموار کر دی جائے گی.وَّ جَآءَ رَبُّكَ وَ الْمَلَكُ صَفًّا صَفًّاۚ۰۰۲۳ اور تیرا رب آئے گا اور فرشتے اس کے ساتھ صف باندھے ہوں گے.حلّ لُغات.دُکَّت.دُکَّتْ.دَکَّ سے مجہول مؤنث کا صیغہ ہے اور دَکَّ الْاَرْضَ کے معنے ہیں سَوّٰی صَعُوْدَھَا وَھَبُوْطَھَا وَکَسَـرَ حُفْرَتَـھَا بالتُّـرَابِ وَسَوّٰھَا یعنی زمین کے اونچے نیچے کو برابر کر دیا (اقرب) پس دُکَّتِ الْاَرْضُ کے معنے ہوں گے جب زمین ہموار کر دی جائے گی.تفسیر.فرماتا ہے کَلَّا تم میں یہ باتیں نہیں ہیں لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت میں یہ سب باتیں پائی جاتی ہیں.تم خوب یاد رکھو جب زمین کو ہلایا جائے گا اور وہ وقت آئے گا جس کی اِذَازُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَھَا (زلزال:۲) میں خبر دی گئی ہے اور خدائی فیصلے کا دن آ جائے گا.اس دن خدا اپنے فرشتوں کی صفوں
Page 286
کے ساتھ آئے گا یا خدا آئے گا اور فرشتے صفیں باندھے کھڑے ہوں گے دونوں معنے ہوسکتے ہیں یہ بھی کہ فرشتے صفیں باندھے کھڑے ہوں گے اور یہ بھی کہ خدا فرشتوں کی صفوں کے ساتھ آئے گا.وَ جِايْٓءَ يَوْمَىِٕذٍۭ بِجَهَنَّمَ١ۙ۬ يَوْمَىِٕذٍ يَّتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ اور اس دن جہنم (قریب) لائی جائے گی اس دن انسان نصیحت حاصل کرے گا.وَ اَنّٰى لَهُ الذِّكْرٰى ؕ۰۰۲۴ مگر اب اس کے لئے (نفع مند) نصیحت کہاں.تفسیر.اَلْاِنْسَانُ سے مراد وہ انسا ن ہے جس کا اوپر ذکر آ چکا ہے اور جس کے متعلق بتایا جا چکا ہے کہ وہ یتامیٰ کی خبر گیری نہیں کرتا.مساکین کو کھانا نہیں کھلاتا.باپ دادا کا مال برباد کر دیتا ہے اور مال سے بے جا محبت کرتا ہے فرماتا ہے اس دن وہ انسان جس میں یہ چار خصلتیں پائی جاتی ہوں گی وہ چاہے گا کہ اپنی اصلاح کرے اپنی قوم کو منظّم کرے.ا پنے شیرازہ کو متحد کرے اور قومی تباہی سے محفوظ رہے مگر اَنّٰى لَهُ الذِّكْرٰى قومی کیریکٹر سالہاسال کی محنت کے بعد پیدا ہوتے ہیں یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ادھر خیال آئےاور ادھر قومی کیریکٹر کا رخ بدل جائے.اکرامِ یتیم کی عادت کسی جماعت میں ایک دن میں پیدا نہیں ہو سکتی بلکہ چالیس پچاس بلکہ سو سال کی جدوجہد کے بعد قومی طور پر جماعت کا ہر فرد اس کیریکٹر کا مالک بنتا ہے.اسی طرح مساکین کی خبر گیری کا قومی طور پر احساس سالوںکی جدو جہد کے بعد پیدا ہوتا ہے.یہی حال محبتِ مال کا ہے کہ وہ ایک دن میں نہیں جاتی بلکہ مدتوں کی کوششیں صفائی قلب کا موجب بنتی ہیں.پس فرماتا ہے اَنّٰى لَهُ الذِّكْرٰى اب اصلاح کا کہاں موقع ہے یہ چیزیں تو ایک لمبے عرصہ میں پیدا ہوتی ہیں اور تمہارا وہ عرصہ گذر گیا اب تو تم ہلاکت کے کنارے پر کھڑے ہو اب اصلاح اور درستی اَحوال کا کون سا موقع ہے.
Page 287
يَقُوْلُ يٰلَيْتَنِيْ قَدَّمْتُ لِحَيَاتِيْۚ۰۰۲۵ وہ کہے گا کاش میں نے اپنی (اس) زندگی کے لئے کچھ آگے بھیجا ہوتا.تفسیر.اس دن اسے اس امر پر افسوس ہو گا کہ کاش میں اعلیٰ اخلاق پیدا کر کے اپنی جماعت کو مضبوط کرتا مگر اس دن کی خواہش نفع نہیں بخش سکتی وہ وقت تو اس کی تباہی کا ہو گا.فَيَوْمَىِٕذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهٗۤ اَحَدٌۙ۰۰۲۶ پس اس دن اس (یعنی خدا) کے عذاب جیسا کوئی عذاب نہ دے گا وَّ لَا يُوْثِقُ وَ ثَاقَهٗۤ اَحَدٌؕ۰۰۲۷ اور نہ اس کی گرفت جیسی کوئی گرفت کرے گا.حل لغات.یُوْثِقُ.یُوْثِقُ: اَوْثَقَ سے مضارع کا صیغہ ہے اور اَوْثَقَہٗ فِی الْوَثَاقِ کے معنے ہوتے ہیں شَدَّہٗ بِہٖ اس کو رسّہ میں یا کسی اور باندھنے والی چیز میں جکڑ دیا (اقرب) پس لَا يُوْثِقُ وَثَاقَهٗۤ اَحَدٌکے معنے ہوں گے اس جیسا کوئی نہیں باندھے گا.تفسیر.فرماتا ہے جس طرح تم نے ایسے ایسے عذاب ہماری جماعت کو دیئے جن کی مثال نہیں ملتی اسی طرح ہم تمہیں بھی اس دن ایسا عذاب دیں گے جس کی مثال نہیں ملتی اور جس طرح تم نے مومنوں کو کئی قسم کی قیدوں میں ڈالا تھا اسی طرح ہم بھی تمہیں قیدوں میں ڈالیں گے.قید سے مراد یہاں صرف قید ہی نہیں بلکہ کاموں سے الگ کر دینا یا اور کئی رنگ میں ان کو جکڑ کر تکالیف پہنچانا بھی اس میں شامل ہے.فرماتا ہے جس طرح تم نے ہمارے مامور کی جماعت کو باندھ باندھ کر دکھ دیئے تھے اسی طرح ہم بھی تم کو ایسا باندھیں گے کہ کبھی کسی کو نہ باندھا ہو گا.
Page 288
يٰۤاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَىِٕنَّةُۗۖ۰۰۲۸ اے نفس مطمئنہ! ارْجِعِيْۤ اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةًۚ۰۰۲۹ اپنے رب کی طرف لوٹ آ (اس حال میں کہ تو اسے) پسند کرنے والا بھی (ہے) اور اس کا پسندیدہ بھی (ہے) تفسیر.نفس مطمئنہ سے مراد وہ نفس ہے جس میں اوپر کی بیان کردہ چاروں خوبیاں پائی جاتی ہوں.اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ جس قوم میں یہ چار خوبیاں پیدا ہو جائیں وہ ہر قسم کے تنزل اور ادبار کے خوف سے مطمئن ہوجاتی ہے.جب یتیم پروری کا مادہ قوم کے ہر فرد کے دل میں پیدا ہو جائے انہیں اپنی موت سے کیا گھبراہٹ پیدا ہو سکتی ہے یا جب مساکین کی خبرگیری کا احساس ہر شخص کے دل میں پیدا ہو جائے اور وہ ایک دوسرے کو اس کی تحریک کرتے رہتے ہوں تو قومی جنگوں کے وقت انہیں کیا خطرہ ہو سکتا ہے.مساکین جن کا بوجھ قوم اٹھا رہی ہو گی آگے بڑھیں گے اور ہر قسم کی تکلیف کو خوشی سے برداشت کرنے کے لئے تیار ہو جائیں گے وہ سمجھیں گے کہ جب قوم ہمارا خیال رکھتی ہے، ہمارے لئے کھانا مہیا کرتی ہے، ہمیں کپڑے پہناتی ہے، ہماری ضروریات کو پورا کرتی ہے تو اب ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم قومی مصیبت میں اس کا ہاتھ بٹائیں اور اس کی عزت کو برقرار رکھنے میں کسی قسم کی قربانی سے دریغ نہ کریں.یا جب اسراف کی عادت قوم کے کسی فرد کو نہیں ہو گی تو نکما پن ان میں کس طرح پیدا ہو سکتا ہے.ان کو خواہ لاکھوں کی جائیداد مل جائے انہیں محنت سے کوئی عار نہیں ہو گی اور جن لوگوں کو محنت سے عار نہ ہو جو کروڑ پتی ہونے کے باوجود خود کماکر کھانے کے عادی ہوں یا روپیہ کو قومی ضروریات پر صرف کرتے ہوں ان کا وجود قوم کے لئے ترقی کا ہی باعث ہو سکتا ہے تنزل کا باعث نہیں ہو سکتا.یا جب ان کے دلوں میں مال کی محبت نہیں ہو گی تو غداری کرنے والے لوگ ان میں کس طرح پیدا ہو سکتے ہیں اور انہیں اپنے متعلق کیا گھبراہٹ ہو سکتی ہے وہ قوم یقیناً مطمئن ہو گی جان کی قربانی کا سوال آئے گا تو لوگ کہیں گے ہمیں اپنی جانوں کی پروا نہیں.ہماری قوم یتیموں کی پرورش کرے گی.اگر مال کی قربانی کا سوال آئے گا تو لوگ کہیں گے ہمیں اپنے مالوں کی پروا نہیں.ہماری قوم وہ ہے جو اپنے مساکین کا خیال رکھتی ہے اس لئے ہم ہر خطرہ سے بے نیاز ہو کر قربانی کی آگ میں اپنے آپ کو جھونکنے کے لئے تیار ہیں اور ہمیں اپنے عواقب سے پوری طرح اطمینان ہے.
Page 289
قومی ترقی کا یہی نکتہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے يٰۤاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَىِٕنَّةُ اے نفس مطمئنہ یعنی پہلاانسان تو وہ تھا جس میں یہ چار خصلتیں مفقود تھیں مگر تو وہ ہے جس میں یہ چاروں خوبیاں پائی جاتی ہیں اس لئے تجھے نفسِ مطمئنہ حاصل ہے ارْجِعِيْۤ اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً اے میرے بندے تو نے دنیا میں رہ کر وہ کام کر لیا جس کےلئے میں نے تجھے پیدا کیا تھا اس لئے تو بھی خوش ہے کہ میں نے کام کر لیا اور ہم بھی خوش ہیں کہ تو نے کام کر لیا.تو ہم سے خوش ہے اور ہم تجھ سے خوش ہیں.فَادْخُلِيْ فِيْ عِبٰدِيْۙ۰۰۳۰ پھر (تمہارا رب تمہیں کہتا ہے کہ) میرے (خاص) بندوں میں داخل ہو جا.تفسیر.فرماتا ہے اب تو ہمارے بندوں میں داخل ہو جا یعنی جس طرح انسان اپنے ماتحت افراد یا اپنی مملوکہ اشیاء کی حفاظت کرتا ہے اسی طرح اب تجھ پر حملہ کرنا مجھ پر حملہ کرنا ہے.تجھے دکھ دینا میری غیرت کو بھڑکانا ہے.تو میرے غلاموں میں داخل ہو گیا ہے اب کسی کی مجال نہیں کہ وہ تجھ پر ہاتھ ڈال سکے.اگر اس کے بعد بھی کسی شخص نے تجھ کو غلام بنانا چاہا تو چونکہ تو میرا غلام ہے اس لئے میں خود اس سے لڑوں گا اور اسے اس اہانت کی سزا دوں گا.وَ ادْخُلِيْ جَنَّتِيْؒ۰۰۳۱ اور (آ) میری جنت میں بھی داخل ہو جا.تفسیر.دنیا میں لوگ غلاموں سے بڑی بڑی خدمتیں لیتے اور انہیں کئی قسم کے عذابوں میں مبتلا رکھتے ہیںمگر فرماتا ہے جو میرا غلام بن جائے میں اسے اپنی جنت میں لے جاتا ہوں.تو چونکہ میرا غلام بن گیا ہے اس لئے اے میرے بندے آ اور میری جنت میں داخل ہو جا.
Page 290
سُوْرَۃُ الْبَلَدِ مَکِّیَّۃٌ سورۃ البلد.یہ سورۃ مکی ہے وَھِیَ عِشْـرُوْنَ اٰیَۃً دُوْنَ الْبَسْمَلَۃِ وَ فِیْـھَا رُکُوْعٌ وَّاحِدٌ اور اس کی بسم اللہ کے علاوہ بیس آیات ہیں اور ایک رکوع ہے.سورۃ البلد مکی ہے سورۃ البلد کے متعلق حضرت ابن عباسؓ اور ابن زبیرؓ کہتے ہیں کہ یہ سورۃ مکی ہے.لطف یہ ہے کہ مسیحی مصنّفین میں سے پادری ویری تک کہتے ہیں.تغلیط کے خطرہ بغیر اس اطمینان اور یقین کے ساتھ کہ ہم کسی غلطی کا ارتکاب نہیں کر رہے.نہ تاریخی واقعات کے خلاف ہم کسی رائے کا اظہار کر رہے ہیں.ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پہلے سال کی ہے.گویا وہ اس کے ابتدائی ہونے پر اتنے مصرّہیں کہ اسے نہ صرف ابتدائی مکی سورتوں میں شمار کرتے ہیں.بلکہ پہلے سال کی نازل شدہ بتاتے ہیں.اگر ایسا ہو تو اس کا مضمون اور بھی معجزانہ ہے.مگر میرے نزدیک اس سورۃ کا ان مضامین سے تعلق ہے جن مضامین کی پہلے تین سورتیں گذر چکی ہیں اور جو تیسرے یا چوتھے سال بعد نبوت کی ہیں.اس بنا پر یہ سورۃ بھی میرے نزدیک تیسرے سال کے آخر یا چوتھے سال کے پہلے چند ماہ کی ہے اور پہلی سورتوں کے زمانہ کی ہی ہے.سورۃ البلد کا تعلق پہلی سورتوں سے اس سورۃ کا تعلق پہلی سورتوں سے یہ ہے کہ پہلی سورتوں میں ظلم کے ابتدا کی خبر دی گئی تھی.اور یہ بتایا گیا تھا کہ مسلمانوں کے خلاف کفار کی طرف سے منظّم کوششیں شروع ہونے والی ہیں.پھر یہ بتایا تھا کہ وہ کوششیں بڑی تکلیف دہ ہوں گی.اور ایک لمبے عرصہ تک (جو دس سال تک ممتد ہو گا) یہ کوششیں جاری رہیں گی.پھر اس کے ازالہ کی صورت پیدا ہو گی.اس کے بعد پھر کچھ تکلیف ہو گی مگر صرف کچھ عرصہ تک رہے گی.اس کے بعد فجر کا طلوع شروع ہو جائے گا.اب اس سورۃ میں اللہ تعالیٰ ظلم کے مقام کو واضح کرتا ہے.اسی طرح ظلم کی بعض اور تفصیلات کو بیان کرتا ہے.اور بتاتا ہے کہ یہ ظلم مکہ میں ہی شروع ہو گا.ہو سکتا تھا کہ چونکہ اس وقت تک مسلمانوں پر ظلم نہیں ہوا تھا.اور رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم اور صحابہؓ کے رشتہ دار مکہ میں موجود تھے.یہ خیال کر لیا جاتا کہ لیالی عشر کی پیشگوئی کا جو ظہور ہونے والا ہے ممکن ہے اس رنگ میں ہو کہ بعض اور علاقوں میں
Page 291
اسلام پھیلے.اور وہاں مسلمانوں پر مظالم شروع ہو جائیں.اس خیال کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ مکہ سے باہر بھی اکّے دکّے لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا تھا.اور ذہن اس طرف جا سکتا تھا کہ ممکن ہے عرب کا کوئی اور حصہ ہو جس میں ان مظالم کا آغاز ہونے والا ہو.یا کوئی اور لوگ ہوں جن کو مصائب و آلام کا تختۂ مشق بنایا جانے والا ہو.اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ میں ایسے شبہات کی تردید کی ہے.اور بتایا ہے کہ تمہارا یہ خیال صحیح نہیں.یہی مکہ جس میں تم رہتے ہو جس میں تمہارے عزیز اور رشتہ دار موجود ہیں.اور جس میں کفار کی طرف سے مظالم شروع ہونے کا تمہارے دلوںمیں خیال تک بھی پیدا نہیں ہوتا.اسی مکہ میں ان کی طرف سے یہ افعال ہوں گے اور اسی شہر میں تم پر مظالم کے تیر برسائے جائیں گے.بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۰۰۱ (میں) اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا (اور) بار بار رحم کرنے والا ہے (شروع کرتا ہوں) لَاۤ اُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِۙ۰۰۲ نہیں (نہیں ایسا نہیں جیسا تم سمجھتے ہو) میں تو قسم کھاتا ہوں اس شہر کی.تفسیر.لَاۤ اُقْسِمُ.لا کے متعلق نحوی لکھتے ہیں کہ فِیْہِ وَجْھَانِ اَحْدُھُمَا ھِیَ زَائِدَۃٌ کَمَا زِیْدَتْ فِیْ قَوْلِہٖ تَعَالٰی لِئَلَّا يَعْلَمَ یعنی اس آیت میں جو لا آتا ہے اس کے متعلق دو باتیں بیان کی جاتی ہیں.ایک تو یہ کہ یہ زائدہ ہے جیسے قرآن کریم میں ہی آتا ہے لِئَلَّا يَعْلَمَ تا کہ وہ نہ جانے اور مراد یہ ہے کہ وہ جان لے.(املاء مامن بہ الرحـمٰن الـجزء الثانی سورۃ القیامۃ ) اس جگہ یاد رکھنا چاہیے کہ زائدہ سے اردو والا زائد مراد نہیں.اردو میں زائد کے اور معنے ہوتے ہیں.اور عربی میں نحویوں کے نزدیک زائد بالکل اور معنی رکھتا ہے.ان کے نزدیک زائد کے معنی صرف اتنے ہوتے ہیں کہ یہ لفظ اپنے لغوی معنوں میں استعمال نہیں ہوا.بلکہ صرف مضمون کی تاکید کے معنی دیتا ہے.(املاء مامن بہ الرحمٰن الـجزء الثانی سورۃ القیامۃ ) پس نحوی جب کسی لفظ کے متعلق یہ کہیں کہ وہ زائد ہے تو اس سے ان کی مراد صرف اتنی ہوتی ہے کہ لغت کے لحاظ سے جن معنوں میں عام طور پر یہ لفظ استعمال ہوا کرتا ہے ان معنوں میں یہ استعمال نہیں ہوا بلکہ تاکید کے معنے دیتا ہے.عربی زبان کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ کئی قسم کے فلسفیانہ نکتے اپنے اندر رکھتی ہے.چنانچہ
Page 292
یہ قاعدہ ایک فلسفیانہ اصل کے ماتحت بنایا گیا ہے انسانی فطرت میں یہ داخل ہے کہ جب عام رسم ورواج کے خلاف کوئی بات کہی جائے تو انسان کی توجہ ادھر پھر جاتی ہے.مثلاً بچے کو بعض دفعہ باتوں باتوں میں انسان کہہ دیتا ہے.’’او شریر‘‘ اب ہر شخص جانتا ہے کہ اس وقت اسے گالی دینا مدنظر نہیں ہوتا.بلکہ صرف اس کی چالاکی کا اظہار مدنظر ہوتا ہے.مگر اس کے لئے شریر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے.جس کے معنے صرف اتنے ہوتے ہیں کہ تیرے افعال میں ایک حدّت اور تیزی پائی جاتی ہے.یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ حدّت اور تیزی اعلیٰ اخلاق یا صحیح مذاق کے خلاف ہو.اسی طرح ماں کے سامنے بعض دفعہ بچہ ایسے انداز سے آتا ہے کہ وہ سمجھتی ہے اب یہ ضرور مجھ سے کوئی چیز مانگے گا وہ اسے دیکھتی ہے اور مسکراتے ہوئے کہتی ہے ’’شریر‘‘ اب اس کے یہ معنی نہیں ہوتے کہ تو بہت برا ہے.بلکہ اس کے معنی صرف اتنے ہوتے ہیں کہ میں جانتی ہوں.تم میری محبت کو کھینچ رہے ہو.اور چاہتے ہو کہ میرے جذبات میں ہیجان پیدا کر کے چیز حاصل کر سکو.اور یہ بات بُری نہیں بلکہ فطرت کے عین مطابق ہے.انسان روزانہ دعائیں مانگتا ہے.اور عجیب عجیب رنگ میں خدا تعالیٰ کے فضل اور اس کے رحم کو حرکت میں لانے کی کوشش کرتا ہے.کبھی کہتا ہے خدایا میں نے فلاں کام محض تیری رضا کے لئے کیا تھا.اگر وہ کام تیری نگا ہ میں پسندیدہ ہے اور تو جانتا ہے کہ میری نیت اور ارادہ اس کام کو کرنے سے محض یہ تھا کہ تیری رضا اور خوشنودی مجھے حاصل ہو جائے.کوئی اور غرض میرے سامنے نہیں تھی.تو اے میرے رب اس نیکی کے عوض میری فلاں حاجت کو پورا فرما دے.کبھی خیال کرتا ہے کہ اگر میں اپنی مسکنت اور غربت خدا تعالیٰ کے سامنے پیش کروں گا تو اس کا رحم جوش میں آ جائے گا.اور اس کا فضل میری مشکل کشائی کا موجب بن جائے گا.چنانچہ اس خیال کے آنے پر وہ اپنے عجز اور اپنی بے کسی کو خدا تعالیٰ کے سامنے پیش کرتا ہے.اور کہتا ہے خدایا میرا تو تیرے سوا کوئی والی اور مدد گار نہیں.میں اکیلا ہوں.میں بے کس اور بے بس ہوں.میری تیرے سوا اور کسی پر نظر نہیں.اگر تو مجھ پر رحم نہیں کرے گا تو اور کون کرے گا.تو میری مدد فرما اور میری مشکلات کو دور کر.کیونکہ تیرے سوا میرا کوئی ناصر اور مدد گار نہیں.اب یہ چالاکی نہیں ہے.نہ اسے شرارت اور بددیانتی کہتے ہیں بلکہ ہر شخص جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو کھینچنے اور اس کے رحم کو جوش میں لانے کے لئے ایسے الفاظ کا استعمال اثر رکھتا ہے.چنانچہ ایک ماں جب اپنے بچہ کو شریر کہتی ہے اس وقت اسے غضب نہیں آتا بلکہ مزہ آتا ہے.اور اس کا جی چاہتا ہے کہ وہ اسے چمٹا لے کہ یہ کتنا ہوشیار ہے اور اس نے اپنے مقصد کو کس عمدگی کے ساتھ پیش کیا ہے.تو فطرت انسانی میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ کبھی کوئی بُری بات بظاہر متضاد کہی جاتی ہے اور اس سے مراد دوسرے کی توجہ کو کھینچنا ہوتا ہے.
Page 293
پنجابی زبان میں بھی بعض دفعہ ایسے الفاظ استعمال کئے جاتے ہیں.جن کا مفہوم ان کے ظاہر کے خلاف ہوتا ہے.مثلاً بعض دفعہ باتیں کرتے ہوئے ایک شخص دوسرے سے کہہ دیتا ہے ’’چھڈ وی‘‘ یعنی مجھے چھوڑو بھی.حالانکہ اس نے اسے پکڑا نہیں ہوتا.نہ اس کا خود یہ مطلب ہوتا ہے کہ تو نے مجھے کیوں پکڑ رکھا ہے.مجھے چھوڑو تاکہ میں جا سکوں بلکہ یہ ایک طریق ہے جو شدت سے دوسرے کو کسی بات سے روکنے کے لئے اختیار کیا جاتا ہے.اسی طرح نحوی کہتے ہیں کہ جب کسی بات کی طرف دوسروں کی توجہ کو مبذول کرنا ہو اور منشا یہ ہو کہ تاکید کی جائے.تو الٹ بات کہہ دی جاتی ہے.حالانکہ مفہوم اور ہوتا ہے جیسے ماں بعض دفعہ اپنے بچہ کو شریر کہہ دیتی ہے.مگر اس کا منشا یہ نہیں ہوتا کہ کسی ناراضگی کا اظہار کرے.بلکہ وہ اپنی محبت کے اظہار کے لئے یہ لفظ استعمال کرتی ہے.اور وہ جانتی ہے کہ جتنی محبت ’’شریر‘‘ کہہ کر ظاہر ہو سکتی ہے.اتنی محبت کسی پیار کے لفظ سے ظاہر نہیں ہو سکتی.گو وہ اسے کہتی ’’شریر‘‘ ہے مگر اس کے چہرے کی بناوٹ اس کے ہونٹوں کی حرکت اور اس کی آنکھوں کی چمک ظاہر کر رہی ہوتی ہے کہ وہ محبت میں گھلی جا رہی ہے.لَاۤ اُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ میں لفظ لَا کے لانے کی فلاسفی غرض لَا کے متعلق نحوی کہتے ہیں کہ یہ زائدہ ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ یہ اصل معنوں میں استعمال نہیں ہوا.بلکہ محض مضمون کی تاکید کے لئے استعمال ہوا ہے.بلکہ اور معنوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَا ’’ نہیں نہیں‘‘ یہ الفاظ ایسے ہیں کہ انسان ان کو سنتے ہی حیران ہو جاتا ہے.اور فوراً اس کی توجہ پھر جاتی ہے کہ یہ ’’ نہیں نہیں‘‘ کیوں کہا جا رہا ہے.اگر صرف اُقْسِمُ سے آیت کا آغاز کیا جاتا ہے اور لَا کا استعمال نہ کیا جاتا.تو اُقْسِمُ کے بعد لوگوں کی توجہ پیدا ہوتی.اور وہ سوچتے کہ ان کے سامنے کون سی شہادت رکھی جا رہی ہے.مگر اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیا کہ لَا ’’نہیں نہیں‘‘ اور باتوں کو چھوڑو اور جو کچھ ہم کہہ رہے ہیںاسے سنو.اس ’’ نہیں نہیں‘‘ کو سنتے ہی ہر شخص فوراً متوجہ ہو جاتا ہے.اور وہ چاہتا ہے کہ میں معلوم کروں کہ کیا بات ہے اور نہیں نہیں کس بات پر کہا جا رہا ہے.گویا لوگوں کی توجہ کو جذب کرنے اور ان پر اصل حقیقت کو ظاہر کرنے کے لئے اُقْسِمُ کی بجائے لَا سے اس سورۃ کا آغاز کیا.تاکہ اُقْسِمُ کے بعد توجہ پیدا نہ ہو.بلکہ اس سے پہلے لَا کے سنتے ہی ہر شخص متوجہ ہو جائے.بعض نحویوں نے کہا ہے کہ یہ لَا زائدہ نہیں بلکہ معنی رکھتا ہے.اور پھر وہ اس کی دو قسمیں کرتے ہیں اَحَدُھُمَا ھِیَ نَفْیٌ لِلْقَسْمِ بِـھَا کچھ لوگ تو کہتے ہیںکہ یہ نفئ قسم کے معنوںمیں ہے.یعنی لَاۤ اُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ کے معنے یہ ہیں کہ ہم اس شہر کی قسم نہیں کھاتے (فتح القدیر سورۃ البلد زیر آیت لَاۤ اُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ ).مگر چونکہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ قسم کی نفی یہاں کیوں
Page 294
کی گئی ہے.اس لئے وہ کہتے ہیں کہ یہاں قسم کی نفی اس لئے کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم جو بات کہتے ہیں وہ اتنی صاف اور واضح ہے کہ اس کے لئے کسی قسم کی ضرورت نہیں.وَالثَّانِیْ اَنَّ لَا رَدٌّ لِکَلَامٍ مُقَدَّرٍ لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ لَا ایک کلام مقدر کا رد ہے (فتح القدیر سورۃ البلد زیر آیت لَاۤ اُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ ).یعنی کوئی اعتراض ہے جس کا لَا کے ذریعہ رد کیا گیا ہے.یہ مقدر کلام دو طرح نکلتا ہے.ایک آیت کے مفہوم سے اور ایک پہلی سورۃ کے مضمون سے یعنی یا تو یہ مقدر کلام آیت کے مفہوم سے نکلے گا.اور یا پھر مقدر کلام وہ ہو گا جس کا پہلے ذکر آ چکا ہے.چنانچہ اس سورۃ میں انہوں نے مقدر کلام پہلی سورۃ کے مضامین سے اخذ کیا ہے اور کہا ہے کہ اس لَا کا مفہوم یہ ہے کہ پہلی سورۃ میں جو باتیں تمہاری طرف سے پیش کی گئی ہیں وہ بالکل غلط ہیں اصل بات اور ہے.اور یا ہماری طرف سے بیان کردہ پہلی باتوں کے خلاف جو لوگ اعتراضات کر رہے ہیں وہ غلط ہیں اور ہم ان کی تردید کرتے ہیں بہرحال انہوں نے لَا کو ایک کلام مقدر کا رد قرار دیا ہے.اور کلام مقدر انہوں نے اس جگہ اَنْتَ مُفْتَرٍ نکالا ہے.یعنی ان لوگوں کا قول یہ ہے کہ وہ کفار جو رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم کو کہا کرتے تھے کہ تو مفتری ہے.ان کا ردّ اس جگہ کیا گیا ہے.اور اصل آیت یوں ہے لَا اَنْتَ لَیْسَ بِـمُفْتَـرٍ نہیں نہیں یہ بات بالکل غلط ہے کہ تو مفتری ہے.تو مفتری نہیں بلکہ ہمارا سچا رسول ہے.اور ہم اس بات کی شہادت کے طور پر اس مکہ شہر کو پیش کرتے ہیں.میرے نزدیک لَا.اَنْتَ مُفْتَرٍ کے جواب میں نہیں بلکہ اسی مضمون کے جواب میں ہے جو پہلی سورتوں کے جواب میں بیان کیا گیا ہے.یعنی مخالفین نے اپنے ذہن میں رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم اور آپ کی جماعت کی تباہی کے منصوبے سوچنے شروع کر دیئے تھے.اور گو ابھی تک انہوں نے ان منصوبوں کو ظاہر نہیں کیا تھا.مگر ان کے اذہان میں یہ بات بڑھتی جا رہی تھی.کہ اب اسلام کو کچلنے اور اس کی ترقی کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے.اور چونکہ انہوں نے مخفی منصوبے کئے تھے میرے نزدیک ان کے ان مخفی خیالات کو قرآن کریم نے بھی ایک اخفا کے رنگ میں پیش کیا ہے.اور لَا کہہ کر ایسے رنگ میں ان کو ظاہر کیا ہے.کہ کفار کو اشاروں اشاروں میں بتا دیا جائے کہ ہمیں تمہارے ان منصوبوں کا علم ہے مگر تم یاد رکھو کہ اپنے ان منصوبوں میں تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے.یہ طریق اللہ تعالیٰ نے سورۃ الغاشیہ سے ہی اختیار کیا ہے.چنانچہ پہلے یہ خبر دی کہ کچھ لوگ عَامِلَۃٌ نَّاصِبَۃٌ بننے والے ہیں.پھر سورۃ الفجر میں خبر دی کہ مسلمانوں پر دس تاریک راتیں آنے والی ہیں.اسی طرح اللہ تعالیٰ اس جگہ ابھی کفار کے ارادوں کو ظاہر نہیں کرتا.صرف اشاروں اشاروں میں ان کا ذکر کرتا ہے.ظاہر اس لئے نہیں کرتا کہ دشمنوں نے بھی ابھی کھلم کھلا مخالفت شروع نہیں کی تھی.صرف مخفی منصوبے اسلام کے خلاف کر رہے تھے.اس لئے
Page 295
اللہ تعالیٰ نے بھی مخفی رنگ میں ان کے منصوبوں کا ذکر کر دیا.اگر ان باتوں کو ظاہر کر دیا جاتا تو سمجھا جاتا کہ مسلمانوں نے ابتدا کی ہے اور انہوں نے خود کفار کو برانگیختہ کیا ہے پس چونکہ اللہ تعالیٰ ابھی کفار کے منصوبوں کو کھلے طور پر ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا.اس لئے اس نے کہہ دیا لَا نہیں نہیں.یعنی میں بتاتا تو نہیں مگر تمہارے دل میں جو کچھ ہے میں اس کی نفی کرتا ہوں اور تمہیں بتاتا ہوں کہ ویسا نہیں ہو گا.اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اشاروں اشاروں میں وہ بات بھی بیان کر دی.مگر ایسی زبان میں کہ جسے ہر شخص نہیں سمجھ سکتا تااشتعال بھی پیدا نہ ہو اور تابعد میں کوئی شخص یہ بھی نہ کہہ دے کہ قرآن کریم نے یوں ہی کہہ دیا تھا کہ ہم سمجھ گئے ہیں.کیونکہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان ایک بات کو نہیں سمجھتا مگر کہہ دیتا ہے کہ میں سمجھ گیا ہوں.مگر واقعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سمجھا نہیں ہوتا اس لئے اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی تشریح کر دی.اور بتا دیا کہ ہم کیا سمجھے ہیں.لیکن ایسی عبارت میں اس کو بیان کیا کہ بات بھی ہو جائے اور وہ یہ بھی نہ کہہ سکیں کہ قرآن کریم نے ان کو اشتعال دلایا ہے یا انگیخت کی ہے اور پہلے ہی کہنا شروع کر دیا ہے کہ کفار مسلمانوں کے متعلق بدا رادے رکھتے ہیں.اس بات کا ثبوت کہ کفار کے ارادوں کا ہمیں پتہ لگ گیا ہے.اللہ تعالیٰ نے آیت کے اگلے حصہ میں دیا ہے جس کی تشریح اپنے موقعہ پر آئے گی.لَا اُقْسِمُ قرآن کریم میں آٹھ جگہ استعمال ہوا ہے.(۱،۲) سورۂ قیامۃ میں دو جگہ (۳)بلد (۴)واقعہ (۵)حاقہ (۶)معارج (۷)تکویر (۸)انشقاق میں اور یہ سب کی سب مکی سورتیں ہیں.قرآن کریم میں جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو بطور شہادت پیش کیا ہے.وہاں عمومًا واؤ سے قسم کھائی ہے.اور جہاں لَا استعمال کیا ہے.وہاں اُقْسِمُ کا لفظ ظاہر کیا ہے.وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الْبُرُوْجِ.وَالسَّمَآءِ وَالطَّارِقِ وغیرہ میں واؤ کا لفظ استعمال کیا ہے.اُقْسِمُ کا لفظ استعمال نہیں کیا.لیکن جہاں لَا کے استعمال کے بعد غیر اللہ کی قسم کھائی گئی ہے وہاں لَا کے بعد اُقْسِمُ کا لفظ آیا ہے واؤ سے قسم نہیں کھائی.جیسا کہ اوپر کی سورتوں میں اس کی مثالیں ملتی ہیں.صرف ایک جگہ ہے جہاں لَا آیا ہے مگر اُقْسِمُ کا لفظ ظاہر نہیں کیا گیا.بلکہ واؤ سے ہی قسم کھائی ہے.اور وہ آیت یہ ہے فَلَا وَ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِيْۤ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا (النساء:۶۶) اس جگہ لَاوَرَبِّكَ فرمایا ہے اُقْسِمُ نہیں فرمایا.لیکن اس آیت کا فرق دوسری اس قسم کی آیتوں سے یہ ہے کہ ان میں قسم غیر اللہ کی کھائی گئی تھی اور اس میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی گئی ہے.اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اُقْسِمُ زور دینے کے لئے اور لَا کے معنوں کو ظاہر کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے.اسی وجہ سے جب خدا تعالیٰ کا نام لیا گیا.جیسا کہ فَلَا وَ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ میں ا
Page 296
میں آتا ہے.تو اس جگہ واؤ کافی سمجھی گئی اور اُقْسِمُ کو ظاہر نہیں کیا.لیکن جہاں خدا تعالیٰ کا نام نہیں لایا گیا.وہاں اُقْسِمُ کا لفظ ضرور لایا گیا ہے اس لئے کہ خدا تعالیٰ کے نام کے متعلق تو ہر شخص جانتا ہے.کہ اس کی قسم کھائی جاتی ہے.لیکن غیر اللہ کے متعلق نہیں جانتا کہ اس کی قسم کھائی جاتی ہے.پس لَا سے چونکہ نفی ہوتی تھی اُقْسِمُ کو ظاہر کر دیا گیا.تا قسم کی نفی نہ سمجھ لی جائے.وَ اَنْتَ حِلٌّۢ بِهٰذَا الْبَلَدِۙ۰۰۳ اس حال میں کہ تو اس شہر میں (ایک فاتح کی صورت میں) اترنے والا ہے.حلّ لُغات.حِلٌّ.حِلٌّ کے معنی ایک تو اس علاقہ کے ہیں مَاجَاوَزَا الْـحَرَمَ مِنْ اَرْضِ مَکَّۃَ جو حرم سے باہر کا ہے.مکہ مکرمہ حرم کہلاتا ہے اور وہاں کسی شکار کا مارنا یا درخت کا کاٹنا بالکل منع ہے.لیکن چند میلوں کے بعد یہ چیزیں جائز ہو جاتی ہیں.یا مثلاً لڑائی حرم میں منع ہے لیکن حرم سے باہر منع نہیں.غرض جو علاقہ مکہ کے اردگرد کی مقررہ حدود کے اندر کا ہے وہ حرم کہلاتا ہے اور اس میں جنگ، شکار اور درختوں کا کاٹنا منع ہے.لیکن حرم سے باہر یہ چیزیں جائز ہیں.اسی وجہ سے بیرونی علاقہ کو حِلٌّ کہتے ہیں.اور اندرونی علاقہ کو حرم.اسی طرح اس کے ایک معنی حلال کے بھی ہیں.یعنی یہ حرام کی ضد بھی ہوتی ہے.وَالْـحِلُّ: اَلْغَرَضُ الَّذِیْ یُرْمٰی اِلَیْہِ.اور حِلّ اس ہدف کو بھی کہتے ہیں جس کی طرف تیر پھینکے جاتے ہیں وَالْاِسْـمُ مِنْ تَـحْلِیْلِ الیَمِیْنِ اور حِلّ تحلیل یمین کا اسم بھی ہے.یعنی قسم کو کسی ذریعہ سے کفارہ دے کر توڑ دینا.چنانچہ حدیثوں میں آتا ہے.رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم نے ایک عورت سے جس نے یہ قسم کھائی تھی کہ میں اپنے غلام کو آزاد نہیں کروں گی.فرمایا حِلًّا اُمَّ فُلَانٍ اَیْ تَـحَلَّلِیْ فِیْ یَـمِیْنِکِ.اے عورت تو کفارہ دے دے اور قسم پر قائم نہ رہ.کیونکہ یہ بری قسم ہے.وَالْـحِلُّ: اَلنَّازِلُ بِالْمَکَانِ اور کسی مکان میں عارضی طور پر اترنے والے کو بھی حِلٌّکہتے ہیں قَالَ الْـحَرِیْرِیُّ مَادُمْتُ حِلًّا بِـھٰذَا الْبَلَدِ اَیْ نَازِلًا اور حریری کہتے ہیں کہ مَادُمْتُ حِلًّا کے معنی یہ ہیں کہ جب تک میں اس شہر میں ہوں (اقرب) حِلٌّ کے پانچ معنے گویا حِلٌّ کے پانچ معنی ہوئے اوّل وہ علاقہ جو حرم سے باہر کا ہے.دوم حلال.سوم ہدف.چہارم قسم کو کفارہ کے ذریعہ توڑنا.پنجم کسی جگہ پر اترنا.
Page 297
تفسیر.اَنْتَ حِلٌّۢ بِهٰذَا الْبَلَدِ کے متعلق علامہ زمخشری لکھتے ہیں کہ یہ جملہ معترضہ ہے جو درمیان میں آ گیا ہے لیکن بحر محیط والے کہتے ہیں کہ یہ جملہ حالیہ ہے (تفسیر بحر مـحیط زیر آیت ’’اَنْتَ حِلٌّۢ بِهٰذَا الْبَلَدِ‘‘) میرے نزدیک جہاں تک متبا درالی الذہن معنوں کا سوال ہے ان کو مدنظر رکھتے ہوئے یہاں واؤ حالیہ ہی زیادہ قرینِ قیاس معلوم ہوتی ہے.مگر اس کے یہ معنی نہیں کہ اس حال میں تو مکہ شہادت ہے لیکن اس کے بغیر کسی روحانی امر کی شہادت مکہ مکرمہ پیش نہیں کرتا.حقیقت یہ ہے کہ کوئی حال تو اس قسم کا ہوتا ہے کہ وہ کسی مزید شہادت کا موجب نہیں ہوتا.لیکن بعض جگہ حال اس شہادت کو دوہرا رنگ دے دیتا ہے اور ایک ہی چیز دو یا دو سے زائد باتوں کے لئے بطور شہادت پیش ہو جاتی ہے.گویا پہلے تو وہ صرف ایک چیز کی شہادت کا موجب ہوتی ہے.مگر اس حال کے ساتھ مل کر دوہری شہادت کا موجب بن جاتی ہے.پس بِھٰذَا الْبَلَدِ کا حال وَاَنْتَ حِلٌّۢ بِهٰذَا الْبَلَدِ کو قرار دینا گویا یہ معنی رکھتا ہے کہ شہادت کے طور پرمکہ کو اس حال میں پیش کیا جاتا ہے جو یہاں بیان کیا گیا ہے مگر اس کے یہ معنے ہرگز نہیں ہیں کہ دوسری صورت میں وہ کوئی نشان نہیں بلکہ یہ حال مزید شہادت کا موجب ہے.ورنہ اس سے کون انکار کر سکتا ہے کہ مکہ وہ شہر ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانۂ کعبہ کی بنیادیں استوار کیں.اور اس نشان عظیم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے تمام عرب کا مرجع بنا دیا.پھر مکہ مکرمہ وہ شہر ہے جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم کی پیدائش سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم الشان نشان دکھایا کہ ابرہہ اپنے لشکر سمیت اس پر حملہ آور ہوا تو خدا تعالیٰ نے اسے اور اس کے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا.اسی طرح چاہ زمزم خدا تعالیٰ کا ایک بہت بڑا نشان تھا.جو مکہ مکرمہ میں پایا جاتا تھا.پھر صفا اور مروہ خدا تعالیٰ کے ایک بہت بڑے نشان کی زندہ یادگاریں تھیں جن کو دیکھ کر انسان کا ایمان تازہ ہوتا تھا اور وہ اللہ تعالیٰ کے ان وعدوں کو اپنی آنکھوں سے پورا ہوتے دیکھتا تھا جو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کی اولاد کے بڑھنے کے متعلق کئے.غرض مکہ مکرمہ اَنْتَ حِلٌّۢ بِهٰذَا الْبَلَدِ کے بغیر بھی اپنی ذات میں خدا تعالیٰ کا ایک بہت بڑا نشان تھا جس سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا.ہر وہ شخص جس کے دل میں ایک ذرّہ بھر بھی ایمان ہو جو خدا تعالیٰ کی قدرتوں کو دیکھنے والی آنکھ رکھتا ہو جو روحانی نابینائی سے محفوظ ہو وہ سمجھ سکتا ہے کہ مکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی ابراہیمی نشانات کی وجہ سے ایک ممتاز مقام تھا.اور وہ اپنی ذات میں خدا تعالیٰ کے وجود کا ایک زندہ گواہ تھا.پس لَاۤ اُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ وَاَنْتَ حِلٌّۢ بِهٰذَا الْبَلَدِ کے یہ معنی نہیں ہیں کہ اس حال کے بغیر مکہ کوئی نشان نہیں تھا.یا وہ خدا تعالیٰ کی ہستی کی کوئی شہادت اپنے اندر نہیں رکھتا تھا.بلکہ اس حال کے معنی یہ ہیں کہ یہ وہ مقدس مقام ہے جس میںعلاوہ اور نشانات کے یہ بھی ایک عظیم الشان نشان پایا جاتا ہے کہ اَنْتَ حِلٌّۢ بِهٰذَا الْبَلَدِ تو اس شہر میں
Page 298
حِلّ ہے جب تک مکہ اس حال سے متصف نہیں ہوا تھا.اس کا نشان اپنی ذات میں اتنا اہم نہیں تھا جتنا اب ہوجائے گا.اس لئے کہ پہلے مکہ مکرمہ اور بات کے ثبوت کے لئے تھا اور اب مکہ مکرمہ اور بات کے ثبوت کے لئے پیش ہونے والا ہے پہلے مکہ مکرمہ ثبوت تھا اس بات کا کہ حضرت ابراہیمؑ خدا کے نبی تھے یا حضرت اسمٰعیلؑ خدا کے نبی تھے.لیکن اب یہ ثبوت ہو گا اس بات کا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم خدا کے نبی ہیں اَنْتَ حِلٌّۢ بِهٰذَا الْبَلَدِ کے بغیر مکہ صرف ان نشانات کا شاہد تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ وابستہ تھے.لیکن اب یہ ان نشانات کا بھی شاہد ہو گا.جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم کی صداقت کے ساتھ وابستہ ہوں گے.پس اس حال نے مکہ کو نیا رنگ دے دیا ہے.پہلے مکہ صرف ابراہیمؑ یا اسماعیل ؑ کی صداقت کا ثبوت تھا.اور اب یہ ثبوت ہو گا اس بات کا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم خدا تعالیٰ کے سچے رسول ہیں.اور دنیا کی کوئی طاقت ان کو اپنے مقصد میں ناکام نہیں کر سکتی.پس اس حال کا یہ مطلب نہیں کہ مکہ صرف اس حال میںشہادت ہے پہلے بطور شہادت اسے پیش نہیں کیا گیا.بلکہ اَنْتَ حِلٌّۢ بِهٰذَا الْبَلَدِ کہہ کر اس طرف اشارہ فرمایا ہے کہ ہم اس وقت اسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم کی صداقت کے ثبوت میں پیش کر رہے ہیں.اگر اس نقطۂ نگاہ کو لیا جائے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کچھ نشانات دکھائے خدا تعالیٰ کی تائید اور اس کی نصرت سے دکھائے تھے.اس وجہ سے مکہ مکرمہ خدا کے وجود کا ایک ثبوت تھا.تو پھر یہ اکٹھا ثبوت بن جائے گایعنی مکہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسمٰعیل علیہما السلام کی صداقت کا بھی ثبوت ہو گا.اور مکہ اس بات کا بھی ثبوت ہوگا کہ خدا موجود ہے کیونکہ حضرت ابراہیمؑ یا حضرت اسمٰعیلؑ نے جو کچھ کیا خدا تعالیٰ کے حکم سے کیا.اور جو کچھ ان کے ہاتھ پر ظاہر ہوا خدا تعالیٰ نے ظاہر کیا.پس جہاں نشانات اور پیشگوئیوں نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسمٰعیل علیہما السلام کی صداقت کا ثبوت دنیا کے سامنے پیش کیا.وہاں خدا تعالیٰ کی ہستی کا ایک زندہ ثبوت بھی لوگوں کے سامنے پیش کر دیا اس لحاظ سے وَاَنْتَ حِلٌّۢ بِهٰذَا الْبَلَدِ کے یہ معنی ہوں گے کہ مکہ مکرمہ پہلے بھی خدا تعالیٰ کی ہستی کا ثبوت تھا.مگر اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم اب تیرے آنے سے یہ ثبوت اور بھی نمایاں ہو گا.کیونکہ تیرے آنے سے خدا تعالیٰ کی طاقتوں اور اس کی قدرتوں کا دنیا میں غیر معمولی ظہور ہو گا.اور ایسے ایسے نشانات ظاہر ہوں گے جو دنیا نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھے.وَاَنْتَ حِلٌّۢ بِهٰذَا الْبَلَدِ کی تفسیر حِلٌّ کے پہلے معنے کے لحاظ سے حِلٌّ کے مختلف معانی جو اوپر بیان کئے جاچکے ہیں ان کے لحاظ سے پہلے معنی وَاَنْتَ حِلٌّۢ بِهٰذَا الْبَلَدِ کے یہ ہوئے کہ ہم اس شہر کو پہلے
Page 299
بیان کردہ مضمون کی تائید میں ایسی حالت میں شہادت کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ اس شہر میں تجھ کو حلال سمجھا گیا ہے یا سمجھا جانے والا ہے.یعنی مکہ مکرمہ کو حرم سمجھا جاتا ہے.اور جو کام باہر جائز ہیں وہ یہاں جائز نہیں اور جو باہر ناجائز ہیں وہ یہاں اور بھی شدت سے ناجائز ہیں.لیکن اے محمد صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم ہم نے جو کہا تھا کہ لیالی عشـر آنے والی ہیں.اس کے متعلق ہم مزید تجھے یہ خبر دیتے ہیں کہ یہ دس تاریک راتیں مکہ مکرمہ میں ہی آنے والی ہیں.پہلے صحابہؓ سمجھتے ہوں گے کہ خواہ مشرکینِ مکہ اسلام کے کس قدر خلاف ہوں اور توحید سے کتنی ہی منافرت کیوںنہ رکھتے ہوں.بہرحال وہ مکہ میں ہمیں کوئی دکھ نہیں پہنچا سکتے کیونکہ ان کا اپنا مذہب یہی ہے کہ باہر تو منع ہے ہی مگر حرم میں قتل و خونریزی اور دنگا وفساد اور بھی سختی سے منع ہے.مگر اَنْتَ حِلٌّۢ بِهٰذَا الْبَلَدِ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ باوجود اس کے کہ مکہ والوں کا مذہب یہی ہے کہ مکہ میں لڑائی جائز نہیں.مکہ والوں کا مذہب یہی ہے کہ مکہ میں فساد جائز نہیں مکہ والوں کا مذہب یہی ہے کہ مکہ میں فتنہ برپا کرنا اور لوگوں کو تکالیف میں مبتلا کرنا جائز نہیں.پھر بھی اَنْتَ حِلٌّۢ بِهٰذَا الْبَلَدِ مکہ کی حرمت تیری اور تیرے ساتھیوں کی حفاظت نہیں کرسکے گی.وہ حرمت تمہیں ان کے حملوں سے بچا نہیں سکے گی.بلکہ تم اس جگہ حلال سمجھے جاؤ گے.بے شک یہاں ہر شے کا مارنا ناجائز سمجھا جاتا ہے یہاں تک کہ شکار تک کا مارنا جائز نہیں مگر اسی مکہ میں اسی شہر کے رہنے والے اور مکہ کی حرمت اور اس کی تقدیس کا عقیدہ رکھنے والے تجھے اور تیرے مریدوں کو اب ہر قسم کی ایذا دیں گے.اور حرم اور اس کی حرمت کا کچھ بھی پاس نہیں کریں گے.اَنْتَ حِلٌّۢ کی تفسیر حِلٌّ کے دوسرے معنے کے اعتبار سے دوسرے معنوں کے لحاظ سے وَاَنْتَ حِلٌّۢ بِهٰذَا الْبَلَدِ کے یہ معنی ہوں گے کہ تو اس میں ہر تیر کا نشانہ بننے والا ہے یعنی یہی نہیں کہ تمہاری عزت یا تمہارا مال ان کے ہاتھ میں محفوظ نہیں ہو گا بلکہ ہر قسم کے مظالم تم پر توڑے جائیں گے.ایک ہوتا ہے ظُلم اور ایک ہوتا ہے ہر قسم کا ظلم.ظلم اپنی ذات میں ہی بُری چیز ہے.لیکن ہر قسم کا ظلم جو شخص اختیار کر لے اور تمام قسم کی برائیوں کے ارتکاب پر کمر بستہ ہو جائے اس سے زیادہ برا اور کون شخص ہو سکتا ہے.اس جگہ نہ صرف مشرکین مکہ کے مظالم کی طرف اشارہ کیا گیا ہے بلکہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہ ہر قسم کے مظالم کا ہدف مسلمانوں کو بنائیں گے اور جو بھی تیر ان کے ہاتھوں سے چھوٹے گا اس کا اولین نشانہ مسلمانوں کے سینے ہوں گے.حِلٌّ کے معنی جیسا کہ حل لغات میں بتایا جا چکا ہے اس ہدف کے ہوتے ہیں جو تیروں کے نشانہ کے لئے بنایا جاتا ہے.پس معنی یہ ہوئے کہ اب تم ہر قسم کے تیروں کا ہدف بن جاؤ گے جو بھی تیر آئے گا تمہاری طرف آئے گا.جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سلسلہ
Page 300
سے پہلے بھی علماء کو کفر بازی کا شوق تھا اور برابر ان کے اندر یہ مشغلہ پایا جاتا تھا کہ کبھی سنیوں نے وہابیوں پر کفر کا فتویٰ لگا دیا اور کبھی وہابیوں نے سنیوں کو کافر قرار دے دیا.کبھی اہل حدیث دیوبندیوں کے خلاف اٹھے اور ان پر کفر کا فتویٰ عائد دیا اور کبھی دیوبندیوں نے دوسرے مسلمان فرقوں کو کافر اور مرتد کہہ کر اپنے دل کو خوش کر لیا.مگر جب سے اللہ تعالیٰ نے احمدیت کو قائم کیا ہے مسلمانوں کی طرف سے جو بھی تیر آتا ہے احمدیوں کی طرف آتا ہے.نہ سنی شیعوں پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں.نہ شیعہ سنیوں کو ملحد اور زندیق کہتے ہیں.بلکہ سب کے سب خواہ وہ سنی ہوں، شیعہ ہوں، اہل حدیث ہوں احمدیت کے خلاف متفقہ طور پر کھڑے ہیں اور انہوں نے ہر تیر کا نشانہ ہماری جماعت کو بنایا ہوا ہے.درحقیقت جس شخص کے متعلق قوم میں یہ احساس پیدا ہو جائے کہ یہ طاقت پکڑتا جا رہا ہے اور ایک دن یہ ہمارے زور کو کچل دے گا.اس کے خلاف ساری قومیں اپنے اختلاف کو بھول کر متحد ہو جاتی ہیں اور متحدہ عزائم سے اس کو مٹانے کی کوشش میں مصروف ہو جاتی ہیں.یہی بات اللہ تعالیٰ نے اس جگہ بیان فرمائی ہے کہ اَنْتَ حِلٌّۢ بِهٰذَا الْبَلَدِ ہر قسم کے مظالم جو پہلے مکہ والوں نے کبھی نہ کئے ہوں گے اور جو مکہ نے کبھی دیکھے بھی نہ ہوں گے وہ اب تم پر اور تمہاری جماعت پر نازل ہوں گے.بے شک مکہ والوں میں اختلاف بھی ہے پارٹیاں بھی ہیں جتھے بھی ہیں مگر تیری مخالفت کی وجہ سے ان کی تمام جتھ بندیاں ختم ہو جائیں گی.وہ سب کے سب اکٹھے ہو جائیں گے آپس کے اختلافات کو بھول کر متحد ہوجائیں گے اور اس ایک مقصد پر سب متفق ہو جائیں گے کہ تجھ پر اور تیرے ساتھیوں پر مظالم کے تیر برسائے جائیں.ا ور ہر قسم کی تکالیف جو وہ پہنچا سکتے ہوں پہنچائیں.یہ بھی کتنی زبردست پیشگوئی ہے کہ نہ صرف مظالم کی طرف بلکہ ان مظالم کے انواع کی طرف بھی اشارہ کر دیا گیا ہے.اَنْتَ حِلٌّ کی تفسیر حِلٌّ کے تیسرے معنے کے لحاظ سے تیسرے معنی اس آیت کے یہ ہوں گے کہ تو اس مقام پر عارضی طور پر اترنے والا ہے یعنی اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم ہم نے لیالی عشر کی پیشگوئی میں مکہ والوں کے جن مظالم کی خبر دی ہے.ان کے نتیجہ میں تجھ کو یہاں سے ہجرت کرنی پڑے گی اور پھر اس کے بعد فاتح کی صورت میں تو اس جگہ واپس آ ئے گا مگر یہاں رہے گا نہیں بلکہ عارضی قیام کے بعد واپس چلا جائے گا.گویا لیالی عشـر اور وَالفجر دونوں کی یہاں تشریح کر دی اور پھر گیارھویں رات کے بعد کی فجر کی طرف بھی اشارہ کر دیا ہے.یہ قرآن کریم کا کیسا کمال ہے کہ اس نے ایک مختصر سے فقرہ میں دو زبردست پیشگوئیاں بیان کر دیں.الف.ہجرت کی.باء.فتح مکہ کی.اور جس طرح اَنْتَ حِلٌّ کے الفاظ میں لیالی عشـر کی تشریح کر دی تھی.اسی طرح اَنْتَ حِلٌّ کے الفاظ نے ہی گیارھویں رات کے بعد کی فجر کو بھی واضح کر دیا اور بتا دیا
Page 301
کہ ہم ان مصائب و مشکلات کے نتیجہ میں تجھ کو مکہ سے لے جائیں گے.مگر پھر تجھے کامیاب و کامران حالت میں اس شہر میں واپس لائیں گے.اَنْتَ حِلٌّ کے چوتھے معنی چوتھے معنی اس آیت کے یہ ہیں کہ تیرے لئے اس مقام میں حلت کی صورت پیدا کی جانے والی ہے یعنی مکہ کا احترام ایسا تھا جیسا کہ کوئی شخص کسی کام کے نہ کرنے پر قسم کھا لیتا ہے.لیکن جس طرح ایک جائز بات اگر حرام ہو جائے تو قسم کا کفارہ دے کر اس کام کو کر لینا جائز ہے.اسی طرح چونکہ مکہ والوں نے اپنی شرارتوں سے اپنے آپ کو عذاب کا مستحق بنا لیا ہے.اس لئے ہم تجھے قسم کا کفارہ دینے والے کی طرح اس ممنوع بات کی اجازت دینے والے ہیں اور اس حرام امر کو تیرے لئے حلال کرنے والے ہیں پس تو اللہ تعالیٰ کی اجازت سے مکہ پر حملہ کرے گا گویا یہ بتایا ہے کہ تجھے اور تیرے ساتھیوں کو مکہ میں حلال سمجھنے کے نتیجہ میں اب ان پر بھی حملہ کرنے کی اجازت دی جائے گی.اگر یہ ظلم نہ کرتے تو ہم شائد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صلحاً اس شہر میں لاتے.مگر چونکہ انہوں نے بلد اللہ الحرام کو حلال بنا لیا.اس لئے کچھ وقت کے لئے ہم بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اس شہر کو حلال کر دیں گے اور پھر جو ان کو ذلت ورسوائی ہو گی اس کے ذمہ وار یہ لوگ خود ہوں گے.گویا صرف یہی نشان نہیں ہو گا کہ تو اس شہر میں کامیاب وکامران واپس آئے گا بلکہ تیرے لئے کچھ وقت تک مکہ کو حلال کر دیا جائے گا اور اہل مکہ کو ان کے مظالم کی وجہ سے شدید رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا.اَنْتَ حِلٌّ کے پانچویں معنی پانچویں معنے اس آیت کے یہ ہیں کہ تو اس میں مقصود ہے ہر ارادہ کا کیونکہ مجازاً ہدف کا لفظ مقصود کے لئے بھی بولا جاتا ہے.اور استعارۃً اس کے ایک معنی امیدوں کے مرجع ہونے کے بھی ہیں.جیسے رَمْیٌ کے معنی تیر پھینکنے کے ہیں اسی طرح رَمْیٌ کا لفظ استعارہ کے طور پر ان اشاروں کے لئے بھی بولتے ہیں جو کسی مامور کے ظہور سے پہلے کئے جاتے ہیں.اس لحاظ سے آیت کے یہ معنے ہوں گے کہ اس شہر کی تقدیس کے لئے جو حالات ظاہر ہوتے رہے ہیں.جیسے حضرت اسمٰعیل علیہ السلام کا مکہ میں آنا، عربوں کا غیر معمولی رجوع، مکہ کا شہر بن جانا، اس کو فتنوں سے پاک رکھنا، اسے دشمن کے حملوں سے محفوظ رکھنا، اسے غیر مذاہب کے اثر سے بچانا.یہ سب باتیں اس شہر کو اس لئے حاصل تھیں کہ تو اس شہر میں ظاہر ہونے والا تھا مگر مکہ والوں کی عجیب حالت ہے وہ یہ تو تسلیم کرتے ہیں کہ مکہ کو عظمت حاصل ہے مگر یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی کہ جس غرض کے لئے مکہ کو عزت دی گئی ہے وہ کیا ہے اور اسی کی وہ مخالفت کر رہے ہیں.بے شک مکہ بڑی عظمت کی چیز ہے.مگر اَنْتَ حِلٌّۢ بِهٰذَا الْبَلَدِ ہم مکہ کو ہی اس بات کی شہادت کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ تو ہی اس شہر کا مقصود ہے اور
Page 302
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ سے لے کر آج تک جو انگلی بھی اٹھ رہی تھی وہ تیری طرف ہی اٹھ رہی تھی.واقعات کا ہر اشارہ تیری طرف تھا اور ہر نشان تیری طرف ہی بنی نوع انسان کی راہنمائی کر رہا تھا مگر تو جو اس شہر کا مقصود ہے جب ظاہر ہو گیا تو مکہ والے تیرے مخالف ہو گئے حالانکہ تو ہی وہ شخص تھا جس کے لئے واقعات کا ایک لمبا سلسلہ ہم نے پیدا کیا.اب اس آیت کے تفصیلی طور پر یوں معنے ہوں گے کہ ہم مکہ کو شہادت کے طور پر پیش کرتے ہیں جس میں کئی قسم کے دردناک مظالم مسلمانوں پر ہونے والے ہیں یعنی ہم نے جو ـظلم اور منظّم سازشوں کے ذکر کئے ہیں خو د یہ مکہ ہی اس بات کا ثبوت دے دے گا اور باوجود اس کے کہ مکہ والوں کا یہ عقید ہ ہے کہ حرم میں شکار تک کو مارنا جائز نہیں.حرم میں کسی انسان کو قتل کرنا جائز نہیں.حرم میں دنگا فساد جائزنہیں.پھر بھی وہ تجھے اور تیرے مریدوں کو اس مکہ میں ہر قسم کی ایذائیں دیں گے اور انہیں حرم اور اس کی تقدیس کا کچھ بھی خیال نہیں رہے گا.یہ واقعہ میں ایک حیرت انگیز چیز تھی جو صحابہؓ کو دیکھنی پڑی صحابہؓ کے لئے کفار کی مارپیٹ اتنی حیرت انگیز نہیں تھی جتنی حیرت انگیز ان کے لئے یہ بات تھی کہ ہمیں مکہ میں مارا جاتا ہے.یہ بات انسانی فطرت میں داخل ہے کہ جب اسے غیر متوقع طور پر کسی کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے تو وہ اسے غیر معمولی طور پر محسوس کرتا ہے اور اس تکلیف سے بہت زیادہ اذیت پاتا ہے.قصہ مشہو ر ہے کہ منصور کے متعلق بادشاہ نے حکم دے دیا کہ انہیں پتھراؤ کیا جائے.لوگ انہیں پتھر مارنے لگ گئے.مگر منصور بالکل خاموش رہے اور انہوں نے اس سخت تکلیف کے باوجود اف تک نہ کی.اسی دوران میں شبلی وہاں سے گذرے جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ منصور کو پتھر ما رہے ہیں تو انہوں نے گلاب کا ایک پھول اٹھایا اور منصور کو مارا.جب گلاب کا پھول ان کے جسم سے لگا تو وہ چلّا اٹھے لوگوں نے ان سے کہا کہ عجیب بات ہے ہمارے پتھروں سے تو آپ کو کوئی تکلیف نہ ہوئی اور آپ خاموش رہے لیکن شبلی نے گلاب کا ایک پھول مارا تو آپ چلّا اٹھے.یہ کیا بات ہے انہوں نے کہا تمہارے پتھر مجھے پھول معلوم ہوتے تھے لیکن شبلی کا پھول مجھے پتھر معلوم ہوا.یعنی اس سے مجھے امید نہیں تھی کہ وہ مجھے مارے گا اور گو اس نے مجھے پھول ہی مارا مگر چونکہ غیر متوقع طور پر اس کی طرف سے ایسا فعل سر زد ہوا اس لئے اس کا پھول مجھے پتھر کی طرح آ کر چبھا اور اس نے مجھے سخت تکلیف پہنچائی.اسی طرح مکہ وہ مقام تھا جہاں کے رہنے والوں کا عقیدہ یہ تھا کہ یہاں کسی پر ظلم کرنا سخت گناہ ہے، کسی کو مارنا سخت گناہ ہے، کسی کو پیٹنا سخت گناہ ہے، کسی سے لڑائی کرنا جائز نہیں.مکہ ایک مقدس مقام ہے اس کی تقدیس اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ یہاں اس قسم کی وحشیانہ حرکات کا قطعاً ارتکاب
Page 303
نہ کیا جائے.چنانچہ سالہا سال سے اس عقیدہ پر ان کا عمل تھا.مکہ کی عظمت اور اس کی حرمت کو پوری طرح ملحوظ رکھا جاتا تھا.لڑائی اور قتل و خونریزی کو حدود حرم میں قطعاً جائز نہیں سمجھا جاتا تھا.یہاں تک کہ وہ قبائل جو حرم کی حدود سے باہر آپس میں دست و گریبان رہا کرتے تھے، جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوتے تھے، جو تلواروں سے ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ رہے ہوتے تھے وہ بھی جب حرم کی حدود میں آتے تو ان کی لڑائیاں ختم ہوجاتیں.وہ ایک دوسرے کے دشمن ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے والے شانہ بشانہ اور کندھا بہ کندھا لَبَّیْکَ اَللّٰھُمَّ لَبَّیْکَ کہتے ہوئے مکہ کا طواف کرتے.اور اس کے گلی کوچوں میں گھومتے ہوئے نظر آتے.کسی کی مجال نہیں تھی کہ وہ حرم میں کسی کو غضب آلود نگاہوں سے دیکھ سکے.مگر اسی مکہ میں اسی حرم کی حدود میں یہی عقیدہ رکھنے والے ایک دن اسلام اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں اس قدر جوش اور غیظ و غضب سے بھر گئے کہ انہوں نے اپنی تلواریں سونت لیں اپنے عقائد کو بالائے طاق رکھ دیا اور انہوں نے متحدہ طور پر یہ فیصلہ کر لیا کہ مسلمانوں کو قتل کر دو، ان پر عرصہ حیات تنگ کر دو، ان کو دکھ دے دے کر اسلام سے منحرف کرنے کی کوشش کرو.اور اس بات کو نظر انداز کر دو کہ یہ حرم ہے یا حرم سے باہر کا علاقہ ہے.مکہ والوں کا حدود حرم میں مسلمانوں کے متعلق یہ فیصلہ ان کے لئے ایسا ہی حیرت انگیز تھا.جیسے منصورکے لئے شبلی کا پھول حیرت انگیز تھا.وہ ان پتھروں کی امید تو کرتے ہی تھے مگر ان کے واہمہ اور گمان میں بھی یہ نہیں آ سکتا تھا کہ شبلی ایک پھول بھی ان پر پھینکنے کی جرأت کرے گا.اس لئے جب شبلی نے پھول مارا تو گو وہ گلاب کا ایک پھول تھا ان کو پتھروں کی بوچھاڑ سے زیادہ سخت معلوم ہوا اور اس کی اذیت نے ان کو پریشان کر دیا.اسی طرح اگر طائف وغیرہ میں مسلمانوں کو مارا جاتا یا ان کو مختلف قسم کے دکھوں میں مبتلا کیا جاتا تو مسلمانوں کے لئے یہ بات ہرگز قابل تعجب نہ ہوتی.وہ سمجھتے کہ یہ باتیں تو انبیاء کی جماعتوں کو پیش آیا ہی کرتی ہیں مگر وہ سمجھتے تھے کہ کفار کے عقیدہ کے مطابق مکہ مکرمہ میں ایسی بات نہیں ہو سکتی.اس لئے انہیں سخت حیرت ہوئی کہ مکہ ہی میں کفار نے مسلمانوں کو مظالم کا تختۂ مشق بنانا شروع کردیا.حالانکہ مکہ والے ابراہیمؑ کے زمانہ سے مکہ کی تقدیس اور اس کی حرمت کے قائل چلے آتے تھے.رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم اور حضرت عیسٰی علیہ السلام کا درمیانی عرصہ چھ سو سال کا ہے.اور حضرت عیسٰی اور حضرت موسیٰ علیہما السلام کا درمیانی زمانہ ۱۳ سوسال کا ہے.یہ ۱۹ سو سال ہوئے.حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی چھ سو سال پہلے ہوئے ہیں.انیس سو سال یہ اور چھ سو سال وہ ۲۵سو سال ہوگئے.گویا اڑھائی ہزار سال سے یہ اعتقاد ان کے اندر قائم چلا آ رہا تھا کہ یہاں کسی کو مارنا پیٹنا سخت گناہ ہے، کسی کی
Page 304
جان لینا سخت گنا ہ ہے، کسی پر ظلم کرنا سخت گناہ ہے.اتنے لمبے عرصہ کے عقیدہ کے بعد کس کو یہ امید ہو سکتی تھی کہ یہ قوم ایک دن مسلمانوں پر یک دم ٹوٹ پڑے گی.اور ان کی عورتوں اور ان کے بچوں ان کے غلاموں اور ان کے آزادوں پر دانت پیستے ہوئے انہیں حدود حرم میں ہی مظالم کا نشانہ بنانا شروع کر دے گی.یہ امید کسی شخص کو بھی نہیں تھی.مگر م ہوا یہی کہ مکہ والوں نے اپنے تمام اعتقادات کو پس پشت ڈال دیا.اور مسلمانوں کو مکہ میں اپنے مظالم کا نشانہ بنانا شروع کر دیا.دوسرے معنے اس آیت کے یہ ہیں کہ تو اس شہر میں ہر تیر کا نشانہ بنے گا.یعنی ہر قسم کے مظالم تم پر اور تمہاری جماعت پر توڑے جائیں گے.یوں تو دنیا میں کبھی رحم دل بھی جوش میں آکر دوسرے کو سزا دینے پر آمادہ ہو جاتے ہیں.اور کبھی جوش پیدا ہونے کی وجہ سے وقتی طور پر انسان کسی وحشیانہ حرکت کا بھی ارتکاب کر لیتا ہے.لیکن لمبی تعذیب جو مارنے سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہے.اس کا امکان ایسے لوگوں سے جو ۲۵سو سال سے ایک خاص قسم کا عقیدہ رکھتے چلے آ رہے ہوں بہت ہی بعید اور دورازقیاس تھی اور کوئی شخص یہ امیدبھی نہیں کر سکتا تھا کہ مکہ والوں کی طرف سے ہر قسم کے مظالم کا ایک لمبا سلسلہ شروع ہو جائے گا.مگر اللہ تعالیٰ نے قبل ازوقت فرما دیا کہ تم مت خیال کرو کہ یہ قوم تم پر ظلم نہیں کرے گی.یا تمہیں معمولی تکالیف دینے پر اکتفا کرے گی.یہ وہ قوم ہے جو ہر قسم کے مظالم کا دروازہ تم پر کھول دے گی اور ہر قسم کے تیروں کا تمہیں ہدف بنالے گی.جو تیر بھی اٹھے گا اس کا نشانہ مسلمانوں کے سینے ہوں گے.اور جو ظلم بھی توڑا جائے گا مسلمانوں پر توڑا جائے گا.چنانچہ اس پیشگوئی کی صداقت کفار مکہ نے اپنے مظالم کے ذریعہ روزروشن کی طرح ظاہر کر دی.دنیا میں ظلم ہوتے ہیں مگر دشمنوں کی طرف سے اگر مذہبی بنا پر کوئی مخالفت ہو تو زیادہ تر علماء مخالف ہوتے ہیں.ماں باپ اور بھائی وغیرہ مذہبی اختلاف کے وقت زیادہ مخالفت نہیں کرتے.بلکہ اگر کسی کا بچہ کسی اور مذہب میں شامل ہو جائے تو ماں باپ کہہ دیا کرتے ہیں کہ اس کی بھی ایک رائے ہے اور ہماری بھی ایک رائے ہے ہم نہیں جانتے کہ سچ کیا ہے.یا زیادہ سے زیادہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے بچے کی یہ غلطی ہے کہ اس نے دوسرا مذہب اختیار کر لیا.لیکن غلطیاں دنیا میں کس سے نہیں ہوتیں.گویا عام طور پر مذہبی اختلاف پر مظالم ڈھانے کی بجائے لوگ اپنے بچوں اور اپنے بھائیوں کا ساتھ دیتے ہیں اور ان کی طرف سے کئی قسم کے عذرات اور حیلے بہانے پیش کئے جاتے ہیں.لیکن یہاں فرمایا کہ ہر قسم کے تیر تم پر چلائے جائیں گے.یعنی ماں تمہاری ماں نہیں رہے گی باپ تمہارا باپ نہیں رہے گا اور تمہیں ہر قسم کے مظالم کا نشانہ بنایا جائے گا.چنانچہ ہم دیکھتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے
Page 305
زمانہ میں مسلمانوں پر صرف دینی علماء نے ظلم نہیں کئے.کاہنوں نے ظلم نہیں کئے.بتوں کے پجاریوں نے ظلم نہیں کئے بلکہ ہر ایک نے ظلم کئے ہیں.حتی کہ ماں باپ نے بھی ظلم کئے ہیں.ایک نوجوان جو ابھی پوری طرح بالغ بھی نہیں ہوا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا.ماں نے غصہ میں آ کر اس کے برتن الگ کر دئیے اور کچھ مدت تک دیکھا کہ اس پر کوئی اثر ہوتا ہے یا نہیں.مگر اس پر کوئی اثر نہ ہوا.اسے ماں باپ نے بہتیرا سمجھایا اور جب وہ زبانی سمجھانے سے باز نہ آیا تو اسے مارا پیٹا.مگر اس نے اسلام کو ترک کرنے سے قطعی طور پر انکار کر دیا.آخر ایک دن اسے ماں باپ نے کہہ دیا کہ تو ہمارے گھر سے نکل جا.وہ نوجوان گھر سے نکلا اور چند دن مکہ میں کئی قسم کی تکالیف اٹھانے کے بعد حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلا گیا (اسد الغابۃ جلد اوّل صفحہ ۶۵۵ زیر حالات خالد بن سعید بن العاص ).جب سورۂ نجم والے واقعہ کی خبر حبشہ میں پہنچی یا جیسا کہ میری تحقیق ہے.سورۂ نجم والے واقعہ کا منصوبہ بنا کر مکہ والوں نے اس کی خبر حبشہ میں پہنچائی تو کئی مسلمان یہ خبر سن کر حبشہ سے واپس آ گئے.انہی میں وہ نوجوان صحابی بھی تھا.وہ اپنے گھر گیا اور اس نے سمجھا کہ شاید اب ان کا غصہ تھم چکا ہوگا.اس کے ماں باپ نے بڑے جو ش سے اس کا استقبال کیا.اسے اپنے گلے سے لگایا اور پیار کیا اور سمجھا کہ اب جو یہ ہمارے گھر آیا ہے تو شاید اسلام سے توبہ کر کے آیا ہے اور اس نوجوان نے خیال کیا کہ میری کئی مہینوں کی جدائی اور مکہ کو چھوڑ کر چلے جانے کا میرے ماں باپ پر یہ اثر ہوا ہے کہ ان کے دل نرم ہوگئے ہیں اور ان میں بھی رحم کے جذبات پیدا ہو گئے ہیں.مگر ابھی وہ بیٹھا ہی تھا کہ ماں نے اسے کہا کہ شکر ہے کہ تیری بھی آنکھیں کھلیں اور تجھے معلوم ہوا ہے کہ تو نے اس صابی (نعوذ باللہ من ذالک)سے تعلق پیدا کر کے اچھا کام نہیں کیا تھا.اب میری یہی نصیحت ہے کہ اُ س صابی (نعوذ باللہ من ذالک) کے پاس کبھی نہ جانا.وہ لڑکا اسی وقت کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا اے میرے ماں تو میری ماں ہے اور اے میرے باپ تو میرا باپ ہے لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم کے لئے میں ہرقسم کی قربانی کرنے کے لئے تیار ہوں اور اس راہ میں کسی بڑی سے بڑی مشکل کی بھی میں پروا نہیں کر سکتا اگر محمدرسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم کے متعلق پھر کوئی ایسا لفظ تم نے اپنی زبان سے نکالا تو نہ تم میری ماں ہو، نہ تم میرے باپ ہو.انہوں نے کہا اچھا اگر یہ بات ہے تو پھر توبھی ہمارا بیٹا نہیں.یہ سنتے ہی وہ اپنے گھر سے باہر نکل گیا اور پھر ساری عمر اس نے اپنے ماں باپ کی صورت نہیں دیکھی.اب دیکھو یہ تیر تو چلے پر کہاں سے؟ اس جگہ سے تیر چلے جہاں سے انسان آخری وقت میں بھی تیر چلنے کی امید نہیں رکھتا اور ان ہاتھوں سے چلے جو عام طور پر تیر چلانے کی بجائے دوسروں کے تیر اپنے ہاتھوں پر
Page 306
لیا کرتے ہیں اور چلنے والے تیروں کے درمیان خود آ کر کھڑے ہو جایا کرتے ہیں.یہ تو ماں باپ کے سلوک کا ایک نظارہ تھا.اب چچا کے سلوک کا ایک نظارہ دیکھ لو.رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم کا ایک چچا ابو لہب تھا.اور بھی آپ کے بعض چچا تھے مگر بجائے اس کے کہ وہ آپ کی مشکلات میں آپ کا ساتھ دیتے وہ خود دوسروں کو انگیخت کیا کرتے.اور ان کورسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اکساتے رہتے تھے.اور تیر تو الگ رہے یہی تیر کیا کم ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم کی دو بیٹیاں رقیہ اور ام کلثوم ؓ آپ کے چچا ابولہب کے دو بیٹوں سے بیاہی ہوئی تھیں.دعویٰ نبوت کے بعد اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم کی مخالفت کی وجہ سے اپنے بیٹوں کو بلایا اور ان سے کہا اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو اپنی بیویوں کو طلاق دے دو.انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دی(الاصابۃ فی تـمییـز الصحابۃ الـجزء الرابع صفحہ ۴۸۹ ،۴۹۰ زیر عنوان ام کلثوم).گویا نازک سے نازک جذبات کو توڑنے کی بھی آپ کے رشتہ داروں نے کوئی پروا نہ کی.وہ بھی ایک چچا ہی تھا جس نے آپ کو پالا اور آپ کی پرورش کی اور وہ بھی ایک چچا ہی تھا جس نے آپ کا مقابلہ کیا اور آپ کو شدید سے شدید دکھ دیا.یہاں تک کہ آپ کی دو۲ لڑکیوں کو بلاوجہ طلاق دلا دی.پھر دوست ہوتے ہیں اور ان میں بڑی گہری دوستی ہوتی ہے مگر جس نے اسلام قبول کر لیا اس کے تمام دوست اس سے بچھڑ گئے.عرب لوگ دوستیوں کو بہت نباہنے والے تھے اور وہ ضرورت پر ایک دوسرے کے لئے جانیں بھی قربان کر دیا کرتے تھے.مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم کے خلاف اتنا بغض مکہ والوں کے دلوں میں پیدا ہوگیا تھا کہ انہوں نے اپنی تمام دوستیوں کو قطع کر کے رکھ دیا اور بڑے بڑے گہرے دوست ایک دوسرے کے جانی دشمن بن گئے.عثمان بن مظعون مکہ کے ایک رئیس کے لڑکے تھے.اسلام لانے پر طرح طرح کے مظالم ان پر ہوئے.آخر ہجرت کے ارادہ سے گھر سے نکلے.راستہ میں ا ن کے والد کا ایک گہرا دوست ملا.اس نے پوچھا کہاں جا رہے ہو.عثمان نے کہا مکہ والوں کے ظلم سے تنگ آ کر ہجرت کر رہا ہوں اس رئیس کی آنکھوں میں یہ سن کر آنسو آ گئے.عثمان کو گلے لگا لیا اور کہا کہ میرے دوست کا بیٹا مکہ چھوڑے یہ نہیں ہو سکتا.تو آج سے میری پناہ میں ہے.چنانچہ واپس آ کر خانۂ کعبہ میں اپنی حفاظت کا اعلان کردیا.مکہ والے ایک دوسرے کی پناہ کا بڑا لحاظ کرتے تھے لوگوں نے اس رئیس کی وجہ سے عثمان کو دکھ دینا چھوڑ دیا.اس سال حج کے موقعہ پر تمام عرب کے لوگ منیٰ میں جمع ہوئے.لبید شاعر اپنے شعر سنا رہے تھے کہ انہوں نے ایک شعر پڑھا.اَلَا کُلُّ شَیْءٍ مَاخَلَا اللہَ بَاطِلُ
Page 307
عثمان نے یہ سن کر صَدَقْتَ کے لفظ کہے یعنی تو نے سچ کہا ہے.لبید جو اس وقت عرب کے سب سے بڑے شاعر سمجھے جاتے تھے.ایک نوجوان سے اپنے کلام کی تصدیق سن کر آگ بگولہ ہو گئے اور کہا کہ کیا لبید کو ایک بچہ سے اپنے شعر کی تصدیق کروانے کی ضرورت ہے.مکہ والو تمہارے اخلاق کو کیا ہو گیا.اس پر لوگ غصہ سے عثمان کی طرف لپکے اور انہیں بولنے سے سختی سے منع کیا.اس کے بعد لبید نے دوسرا مصرعہ پڑھا وَ کُلُّ نَعِیْمٍ لَا مَـحَالَۃَ زَائِلُ یعنی ہر نعمت ضرور زائل ہو جائے گی.عثمان نے کہا کَذَبْتَ نَعِیْمُ الْـجَنَّۃِ لَا یَزُوْلُ یعنی تو غلط کہتا ہے.جنت کی نعمتیں زائل نہ ہوں گی.اس پر تو لبید سخت غصہ میں آ گئے اور کہا کہ اب میں شعر نہیں پڑھتا.اس پر نوجوان عثمان کی طرف لپکے.ایک شخص نے شدت غیظ سے ایک گھونسا تان کر عثمان کی آنکھ میں مارا کہ ڈھیلے کا پانی بہہ گیا اور آپ کانے ہو گئے.وہ رئیس جس نے پناہ دی تھی اٹھا اور کہا کہ بےوقوف تو نے کیا کیا کہ اپنی آنکھ ضائع کروا لی.عثمان نے کہا کہ تو اپنی پناہ گھر رکھ.تو کہتا ہے کہ میں نے ایک آنکھ ضائع کر دی.میری دوسری آنکھ بھی خدا تعالیٰ کی راہ میں جانے کو بے تاب ہے(اسد الغابۃ زیر عنوان عثـمان بن مظعون).اب دیکھو کس طرح مکہ میں دوستیاں دھری کی دھری رہ گئیں.اور اسلام کے جرم میں کوئی دوست بھی کسی مسلمان کے کام نہ آیا.بلکہ وہ سارے رشتہ دار، دوست اور قریبی تعلقات رکھنے والے جن سے انسان کو ہمیشہ مہرو وفا کی امید ہوتی ہے جن سے محبت اور پیار کی امید ہوتی ہے.جن سے دکھ اور مصیبت کی گھڑیوں میں حسن سلوک اور ہمدردی کی امید ہوتی ہے.انہی لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے اسلام کی مخالفت میں اپنے عزیزوں پر تیر چلائے.یہاں تک کہ بعض جگہ خاوندوں نے اپنی بیویوں کو چھوڑ دیا.اور بیویاں اپنے خاوندوں سے الگ ہو گئیں.ماں باپ نے اپنے بچوں سے قطع تعلق کر لیا.اور بچوں نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا.پھر یہ نہیں کہ صرف ایک رنگ کا عذاب ان کو دیا گیا ہو.بلکہ ہر نوعیت اور ہرقسم کے مظالم ان پر توڑے گئے.پتھروں پر ان کو گھسیٹا گیا.جلتی ہوئی ریت پر ان کو لٹایا گیا.مکہ کی گلیوں میں جہاں بڑے بڑے کھردرے اور نوک دار پتھر ہوتے تھے.ان کی ٹانگوں میں رسیاں باندھ کر اس طرح گھسیٹا جاتا جیسے کسی مردہ جانور کو گھسیٹا جاتا ہے.یہاں تک کہ ان کا تمام جسم لہولہان ہو جاتا.پھر بسا اوقات ان کو زد وکوب کیاجاتا.ان کے سینہ پر بڑے بڑے وزنی پتھر رکھ کر انہیں مجبور کیا جاتا کہ وہ توحید سے منحرف ہو جائیں.کئی لوگ ایسے تھے جن کو نیزے مار مار کر ہلاک کیا گیا.یہاں تک کہ بعض مسلمان عورتوں کی شرمگاہوںمیں انہوں نے نیزے مار کر ان کو ہلاک کیا.ان کے پاؤں میں بیڑیاں ڈالی گئیں انہیں گندی سے گندی اور غلیظ سے غلیظ گالیاں
Page 308
دی گئیں.ان کو ملک سے نکالا گیا اور ان کو ہلاک کرنے کے لئے نہایت ظالمانہ اور گندے طریقوں کو اختیار کیا گیا.بعض دفعہ مسلمان مردوں کی ایک ٹانگ ایک اونٹ سے اور دوسری ٹانگ دوسرے اونٹ سے باندھ دیتے.اور پھر ان اونٹوں کو مخالف اطراف میں دوڑا دیتے اور اس طرح ان کو ہلاک کر کے اپنے دلوں کو خوش کرتے.غرض کوئی نوعیت ظلم کی ایسی نہیں تھی جس سے مکہ والوں نے کام نہ لیا ہو.اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَ اَنْتَ حِلٌّۢ بِهٰذَا الْبَلَدِ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم تو اس مکہ میں ہر قسم کے تیروں کا ہدف بنے گا.ہر ہاتھ خواہ وہ باپ کا ہو یا ماں کا ہو یا چچا کا ہو یا کسی اور عزیز رشتہ دار کا ہو.تیرے مقابلہ میں اٹھنے والا ہے.اور ہرقسم کا تیر ان کی طرف سے چلنے والا ہے.پھریہ بھی کتنی عظیم الشان پیشگوئی ہے اور کتنی لطیف تفسیر ایک مختصر سے فقرہ میں لیالی عشـر کی فرما دی کہ ایک دن آنے والا ہے جبکہ تو اس مقام پر اترے گا جو اسی وقت ممکن ہو سکتا تھا کہ آپ پہلے مکہ چھوڑ کر جائیں.پس اترے گا کا مختصر لفظ استعمال کر کے ہجرت کی طرف بھی اشارہ کر دیا اور بتایا کہ ظلموں کے بعد تجھے اس شہر سے ہجرت کرنی پڑے گی اس زمانہ کے لحاظ سے یہ بھی کتنی عجیب اور حیرت انگیز بات تھی.مکہ کے لوگوں کی معاش کا ذریعہ صرف باہر سے آنے والے لوگوں کی آمد پر تھا.اور وہ محض مجاوروں کا ایک شہر تھا.ان کا کام یہ تھا کہ وہ لوگوں کو اپنی طرف بلائیں.ان کا یہ کام نہیں تھا کہ وہ مکہ سے لوگوں کو نکالیں.اس زمانہ میں کون کہہ سکتا تھا کہ یہ مجاور ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو مکہ سے نکال دیں گے.یقیناً جہاں تک انسانی قیاسات کا سوال ہے کسی شخص کے وہم اور گمان میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ مکہ والے جو مجاوروں کی سی حیثیت رکھتے ہیں اور جن کی زندگی کا تعلق ہی اس بات سے ہے کہ باہر سے لوگ مکہ میں آتے رہیں.وہ ایک دن اسلام کی مخالفت میں اس قدر اندھے ہو جائیں گے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو اس امر پر مجبور کر دیں گے کہ وہ مکہ کو چھوڑ دیں اور کسی اور شہر میں چلے جائیں.مگر اللہ تعالیٰ نے قبل از وقت بتا دیا کہ گو آج یہ حالات تمہیں ناممکن دکھائی دیتے ہیں اور تم سمجھتے ہو کہ مکہ والے ایسا کہاں کر سکتے ہیں.مگر یقیناً سمجھو کہ وہ دن آنے والا ہے جب تمہیں مکہ کو چھوڑنا پڑے گا.مگر صرف اسی قدر نہیں بلکہ اس کے ساتھ ہی ہم تمہیں یہ بھی خبر دیتے ہیں کہ اس کے بعد ایک دن وہ بھی آئے گا جب پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم اس شہر میں آئیں گے اور اس مکہ کو جس میں سے وہ صرف اپنے ایک ساتھی کے ساتھ نکلے تھے دس ہزار صحابہ سمیت فتح کر لیں گے چنانچہ فرمایا وَ اَنْتَ حِلٌّۢ بِهٰذَا الْبَلَدِ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اس شہر میں اترنے والا ہے.یہ لازمی بات ہے کہ آپ
Page 309
اس شہر میں اسی صورت میں اتر سکتے تھے جب آپ کو پہلے اس شہر سے نکالا جاتا.گویا ایک ہی فقرہ میں ہجرت کی بھی خبر دے دی اور فتح مکہ کی بھی خبر دے دی.اس طلوع فجر کی بھی پیشگوئی کر دی جو لیالی عشـر کے بعد ظاہر ہونے والی تھی اور اس دوسری فجر کی بھی پیشگوئی کر دی.جو گیارھویں رات کے بعد ظاہر ہونے والی تھی.اور جس کا آغاز بدر سے ہوا اور جس کا اتمام فتح مکہ پر ہوا.پھر یہ بتایا گیا ہے کہ ان کے ظلموں کا نتیجہ ان کے حق میں اچھا نہیں ہو گا.کیونکہ اگر یہ ظلم نہ کرتے.تو شاید رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم کو ہم صلح کے ساتھ اس شہر میں لاتے.مگر چونکہ انہوں نے ظلم کیا ہے اور بلد اللہ الحرام کو حلال کر لیا ہے اس لئے کچھ وقت کے لئے ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلوار کے زور سے اس شہر میں داخل ہونے کی اجازت دیں گے اور پھر جو ان کی ذلت و رسوائی ہو گی اس کے وہ خود ذمہ وار ہوں گے.پھر یہ بتایا کہ تو اس شہر کا مقصود ہے.یعنی پیشگوئیاں شروع دن سے جب سے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسمٰعیل علیہماالسلام نے خانۂ کعبہ کی بنیاد ڈالی تیری طرف اشارہ کر رہی تھیں اور اسی وقت سے یہ خبر دے دی گئی تھی کہ ایک عظیم الشان نبی آنےو الا ہے جس کا کام یہ ہو گا کہ وہ تلاوت آیات کرے گاا ور تزکیۂ نفوس کرے گا اور کتاب اور حکمت سکھائے گا جیسا کہ حضرت ابراہیمؑ کی خانہ کعبہ کی بنیاد اونچی کرنے کے وقت کی دعا سے معلوم ہوتا ہے.جو سورۂ بقرہ میں ان الفاظ میں ذکر کی گئی ہے کہ وَ ابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَ الْحِكْمَةَ وَ يُزَكِّيْهِمْ (البقرۃ: ۱۳۰) یعنی اے خدا مکہ کے رہنے والوں میں رسول مبعوث فرما جو تیری آیات ان لوگوں پر پڑھے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھائے اور انہیں پاک کرے.پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہی یہ پیشگوئی تھی اور آپ ہی اس شہر کے مقصود تھے.اس لئے فرمایا کہ جب اس شہر کی بنیاد محض تیرے لئے رکھی گئی تھی تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ مقصد پورا نہ ہو جس کے لئے اللہ تعالیٰ نے اس کارخانۂ عالم کو قائم کیا تھا.اس مقصد کا پورا ہونا تو نہایت ضروری ہے.چنانچہ شروع سے ہی جب یہ بنیاد ابھی ظاہر بھی نہیں ہوئی تھی.حضرت اسمٰعیل علیہ السلام کا مکہ میں آنا، عربوں کا رجوع، اس شہر کا فتنوں سے پاک رکھنا اور غیر مذاہب کے اثرات سے اس کا محفوظ رہنا یہ ساری باتیں آخر کس لئے تھیں.اسی لئے تو تھیں کہ تو اس شہر کا مقصود تھا.اور اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ دنیا میں تیری بعثت ہو.مکہ ایک بے آب وگیاہ وادی میں تھا.کوئی مہذب قوم اس کے اردگرد نہیں رہتی تھی.بلکہ وہ ظالم اور ڈاکو جو کسی قانون کے ماتحت نہیں تھے اس کے چاروں طرف بستے تھے.ان کا دن رات کام یہی تھا کہ وہ آپس میں لڑتے رہیں اور کشت وخون کا بازار گرم رکھیں.مگر ایسے ظالم اور ڈاکو بھی جب لڑتے ہوئے مکہ کے سامنے آتے
Page 310
تو ان کی تلواریں جھک جاتیں اور وہ کہتے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں لڑائی جائز نہیں.پھر عرب لوگ وہ تھے جو اپنا گذارہ نہایت تنگی سے کرتے.انہیں کھانے پینے کے سامانوں کے لحاظ سے کسی قسم کی آسائش اور سہولت میسر نہیں تھی.مگر جب ذی الحجہ کے دن آتے تو وہ اپنے اونٹوں پر کجاوے کستے اور بے آب و گیاہ میدانوں اور بیابانوں میں اپنے اونٹوں کو ایڑیاں مارتے ہوئے مکہ میں آتے اور حج بیت اللہ کے فرض کو سرانجام دیتے.پھر مکہ وہ شہر تھا جسے خدا نے ہر قسم کی آفات سے بچایا اور جب بھی کوئی دشمن اس پر حملہ کرنے کے لئے آگے بڑھا.اللہ تعالیٰ نے اس کو ناکام کیا.ابرہہ آیا اور وہ اس ارادہ سے آیا کہ وہ اس شہر کو تباہ کر دے گا.وہ خانۂ کعبہ کو گرا دے گا.مگر اللہ تعالیٰ نے ابرہہ کے تمام ارادوں اور اس کی تدابیر کو خاک میں ملا دیا اور آسمانی عذاب کا اسے نشانہ بنا دیا.یہ خدا تعالیٰ کا کیسا زبردست نشان ہے جو اس نے مکہ کی حفاظت کے سلسلہ میں دکھایا اور دنیا پر ثابت کر دیا کہ بیت اللہ کا میں محافظ ہوں کوئی اور محافظ نہیں ہے.ابرہہ یمن کا گورنر تھا اور حبشہ کے بادشاہ کی طرف سے مقرر تھا.عرب میں اگر کوئی آباد اور اچھا علاقہ ہے تو وہ یمن کا ہی ہے.بڑا زرخیز علاقہ ہے.زراعت بھی اچھی ہوتی ہے اور پھل بھی وہاں کثرت سے ہوتے ہیں.ایسے آباد علاقہ اور سب سے طاقتور علاقہ کا گورنر جو بہت بڑی فوجوں کا مالک تھا دس ہزار لشکر کے ساتھ آیا اور اس ارادہ اور نیت سے آیا کہ میں مکہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا.مگر خدا تعالیٰ نے اس کے لشکر میں چیچک کی وبا پیدا کر دی.اور حبشی جو اس کی فوج میں شامل تھے وہ ایک ایک کر کے ہلاک ہونے لگ گئے.حبشی لوگوں میں چیچک کا مرض نہایت مہلک ہوا کرتا ہے.اگر کسی حبشی کو یہ مرض ہو جائے تو اس کی موت یقینی ہوتی ہے.دنیا میں مختلف امراض مختلف قوموں سے تعلق رکھتی ہیں.چیچک کا مرض حبشیوں کے لئے نہایت خطرناک ہوتا ہے اور ڈیسنٹری کا مرض یورپین لوگوں کے لئے نہایت خطرناک ہوتا ہے.ہمارے ملک میں لوگوں کی یہ حالت ہوتی ہے کہ ایک شخص اچھا بھلا ہوتا ہے ہل ہاتھ میں لئے اپنی زمین کی طرف جارہا ہوتا ہے کہ راستہ میں اسے کوئی دوست ملتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے سناؤ کیسا حال ہے.وہ کہتا ہے اچھا ہے.صرف کچھ پیچش لگ گئی ہے.لیکن انگریز کو ذرا بھی پیچش ہو فوراً اس کا دل ڈر جاتا ہے.اور وہ خیال کر لیتا ہے کہ اب میری موت قریب آ پہنچی ہے.غرض مختلف امراض کا صرف افراد سے ہی نہیں بلکہ مختلف قوموں سے بھی تعلق ہوتا ہے.اور جب کسی قوم میں اس کا مخصوص مرض پیدا ہو جائے تو وہ قوم تباہ ہونی شروع ہو جاتی ہے.حبشیوں کے لئے چیچک بڑا جان لیوا مرض ہے.وہ اس کا نام بھی سن لیں تو ان کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں.اللہ تعالیٰ نے ایسے سامان پیدا کئے کہ ابرہہ کے لشکر میں چیچک کا مرض پیدا ہو گیا اور سب میں ایک کھلبلی پیدا ہو گئی.یوں مکہ کو فتح کرنا
Page 311
ان کے لئے کوئی مشکل نہیں تھا.وہ سازوسامان اور اسلحہ سے آراستہ تھے اور مکہ والے بالکل نہتّے تھے.وہ ایک باقاعدہ فوج کا مقابلہ کس طرح کر سکتے تھے.مگر خدا تعالیٰ نے ان میں وہ مرض پیدا کر دیا جس کے نام سے ہی حبشیوں کی جان نکل جاتی ہے.چنانچہ اِدھر مرض پیدا ہوا اور ادھر انہوں نے ہتھیار رکھ دیئے کہ اب ہمارا خاتمہ قریب ہے.چنانچہ اس کے بعد ان میں موتیں شروع ہو گئیں اور سارے لشکر میں بھاگڑ مچ گئی.یہ قدرتی بات ہے کہ جب ایک شخص بھاگتا ہے تو دوسرے کے دل میں بھی کمزوری پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے.جب لشکر کا ایک حصہ سراسیمہ اور پریشان ہو کر بھاگا تو دوسرے حصہ کے اوسان بھی خطا ہو گئے اور اس نے بھی بھاگنا شروع کیا.نتیجہ یہ ہوا کہ یمن پہنچنے سے پہلے پہلے اس کے لشکر کا بہت بڑا حصہ برباد ہو گیا اور جس مقصد کے لئے وہ مکہ پر حملہ آور ہوا تھا خدا تعالیٰ نے اس میں اسے خائب وخاسر اور ناکام و نامراد رکھا.اللہ تعالیٰ ان تمام واقعات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے.کہ لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ آخر ہم یہ باتیں کیوں کر رہے تھے.ہم اس دعا کو پورا کرنے کے لئے یہ سب باتیں کر رہے تھےجو ابراہیمؑ نے کی کہ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَ الْحِكْمَةَ وَ يُزَكِّيْهِمْ١ؕ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ(البقرۃ:۱۳۰) اب یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ جو اس شہر کا اصل مقصود تھا جس کے لئے اڑھائی ہزار سال سے مکہ کی بنیاد رکھی گئی تھی جب وہ ظاہر ہو جائے تو خدا اس کی طرف توجہ نہ کرے.پس فرماتا ہے لَاۤ اُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ.وَ اَنْتَ حِلٌّۢ بِهٰذَا الْبَلَدِ ہم شہادت کے طور پر اس شہر کو پیش کرتے ہیں.اس حالت میں جبکہ تو مکہ کی بنیاد کا مقصود ہے تیرے مقصود ہونے کی صورت میں مکہ کی جو قیمت ہے وہ تیرے غیر مقصود ہونے کی صورت میں ہرگز نہیں.مکہ کی عظمت اور اس کا جلال محض تیری وجہ سے ہے.اب اس آیت کے معنے یوں ہوں گے کہ (۱)ہم مکہ کو شہادت کے طور پیش کرتے ہیں جس میں مسلمانوں پر کئی قسم کے مظالم ہونے والے ہیں.یعنی ہم نے گذشتہ سورتوں میں مخالفین اسلام کی جن منظّم سازشوں کا ذکر کیا ہے یہ مکہ خود ان سازشوں کا ثبوت بہم پہنچا دے گا.یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مخالفت تو قیاسی امر ہے.جو مدعی بھی کھڑا ہوتا ہے لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں.یہ تو نہیں ہوتا کہ اس کی باتوں کو سنتے ہی لوگ فوراً ایمان لے آئیں اور کسی قسم کی مخالفت نہ کریں جب بھی کوئی ایسا مدعی کھڑا ہوتا ہے جو دوسروں کے عقائد کے خلاف کوئی بات پیش کرتا ہے.لوگ اس کی مخالفت کے لئے کھڑے ہو جاتے ہیں.اس لئے یہ کہنا کہ میری مخالفت ہو گی اور مسلمانوں کو تکالیف پہنچائی جائیں گی.یہ پیشگوئی کس طرح بن گیا.یہ تو ایک قیاسی امر تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم نے قیاس کر لیا ہو گا کہ چونکہ مکہ والوں کے سامنے
Page 312
میں نے ایک نئی بات پیش کی ہے اس لئے ضروری ہے کہ مکہ والے مخالفت بھی کریں.اس کو پیشگوئی کس لحاظ سے قرار دیا جا سکتا ہے.اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ اوّل تو ہر مدعی کو مخالفت نصیب نہیں ہوتی.دنیا کے متعلق انسانی ارادے بے شک مخالفت پیدا کر دیتے ہیں.مگر الہام کے نازل ہونے کا دعویٰ کرنا یہ کوئی ایسی چیز نہیں جو ضرور مخالفت پیدا کرے.مثلاً اگر کوئی شخص اس ارادہ سے کھڑا ہو جائے کہ وہ دوسرے کے گھر پر قبضہ کر لے گا تو دوسرا شخص اس سے ضرور لڑے گا.لیکن اگر وہ یہ کہے گا کہ مجھے الہام ہوتا ہے تو دوسرے کو کوئی غصہ نہیں آئے گا.وہ زیادہ سے زیادہ یہی سمجھے گا کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے.جو ایسی باتیں کہتا ہے تو یہ بات بالکل غلط ہے کہ جو بھی مدعی الہام دنیا میں کھڑا ہو ضرور اس کی مخالفت ہوتی ہے.مجھے ایک دفعہ ظہیر الدین اروپی نے جو مصلح موعود ہونے کا مدعی تھا بڑے جوش سے لکھا کہ میں اتنے عرصہ سے آپ کے خلاف اشتہار اور ٹریکٹ وغیرہ شائع کر رہا ہوں مگر آپ ان میں سے کسی کا جواب ہی نہیں دیتے.میں یہ نہیں کہتا کہ آپ مجھے مان لیں.مگر یہ کیا بات ہے کہ آپ بالکل خاموش بیٹھے ہیں اور مخالفت بھی نہیں کرتے.اگر آپ اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم مخالفت ہی کریں خاموش کیوں بیٹھے ہیں.میں نے اسے جواب میں لکھا کہ مخالفت بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے نصیب ہوتی ہے اور یہ بھی سچائی کی ایک علامت ہوتی ہے.اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہا کہ تمہارے اندر یہ علامت بھی پائی جائے.اس لئے خواہ تم کتنی ہی خواہش رکھو کہ لوگ تمہاری مخالفت کریں تمہیں یہ مخالفت بھی نصیب نہیں ہو سکتی.حقیقت یہ ہے کہ یہ خیال بالکل غلط ہے کہ جو مدعی بھی کھڑا ہو لوگ اس کے مخالف ہو جاتے ہیں.مخالفت بھی آسانی سے حاصل نہیں ہوتی.بلکہ یہ بھی خدا تعالیٰ کے فضل کے نتیجہ میں حاصل ہوتی ہے چنانچہ دیکھ لو احمدیت کی مخالفت ہر ملک میں ہوئی لیکن بہائیت کی مخالفت اس طرح نہیں ہوئی.صرف بابیوں کی مخالفت ایران میں ان کی سیاسی چالوں کی وجہ سے ہوئی.حالانکہ وہ لوگ قرآن کو منسوخ قرار دیتے اور بہاء اللہ کی شریعت اس کی بجائے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں.مسلمان یہ سب باتیں دیکھتے اور جانتے ہیں مگر اس کے باوجود وہ بہائیوں کی کوئی مخالفت نہیں کرتے.بلکہ ان کو اپنے گلے سے لگاتے ہیں.لیکن جہاں احمدیت کا ذکر آ جائے وہاں فوراً مخالفت کے لئے کھڑے ہو جاتے ہیں.پس اوّل تو یہ بات ہی غلط ہے کہ مخالفت ایک قیاسی امر تھا.اور ضروری تھا کہ لوگ آنحضرتؐکو اور آپ کے ساتھیوں کو تکالیف میں مبتلا کرتے.دوسرے سوال یہ ہے کہ اگر یہ قیاس ہی تھا تو نبوت کے دعویٰ کے تین سال کے بعد کیوں پیدا ہوا.شروع شروع میں ہی یہ قیاس کیوں نہ کر لیا گیا کہ مکہ والوں کی طرف سے اسلام کی شدید مخالفت ہو گی.پھر ایک اور بات یہ ہے کہ ایک مخالفت وہ ہوتی ہے جو انسان خود کرواتا ہے.مثلاً کسی شخص نے ارادہ کیا کہ
Page 313
وہ دوسرے کی بھینس چوری کرے.یا اس نے ارادہ کیا کہ وہ دوسرے کے گھر پر قبضہ کر لے.اب اگر وہ اپنے ارادہ کا علم رکھتے ہوئے دوسرے کو قبل از وقت خبر دے دے کہ فلاں شخص فلاں دن مجھ سے لڑے گا.تو یہ ہرگز پیشگوئی نہیں ہو گی.کیونکہ یہ فساد اس کے نفس کی طرف سے ہے اور وہ اپنے ارادوں کو جانتے ہوئے کہہ سکتا ہے کہ فلاں فلاں شخص میرے ساتھ لڑائی کریں گے.لیکن اگر اس کی طرف سے صلح کے سامان ہو رہے ہوں محبت اور پیار کی تعلیم دی جا رہی ہو تو ایسی حالت میں کسی مخالفت کے متعلق قیاس نہیں کیا جا سکتا.پس مخالفت خود اکسا کر لانا اور شے ہے اور امن پسند ہونے کے باوجود لوگوں کا مخالفت کرنا اور امر ہے.کسی کے گھر پر تم قبضہ کر لو تو وہ ضرور لڑے گا.اور اس فساد کی تم اپنے ارادہ کو جانتے ہوئے قبل از وقت خبر بھی دے سکتے ہو.مگر تم اپنے گھر میں بیٹھے ہو اور کوئی دوسراشخص تمہارے گھر پر آ کر قبضہ کر لے تو تم کو اس کا کیا علم ہو سکتا ہے.رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم اور آپ کے دشمنوں کا مقابلہ ایسا ہی تھا.آپ صلح و آشتی کا پیغام دیتے تھے اور مخالفین مخالفت پر کمر بستہ ہو جاتے تھے.آخروہ کون سی چیز تھی.جو آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم کے دعویٰ کے تین سال بعد مسلمانوں میں زائد طور پر پیدا ہو گئی تھی اور جس کی بنا پر انہوں نے مخالفت کرنا ضروری سمجھا.نمازیں وہ پہلے بھی پڑھا کرتے تھے نیکی اور تقویٰ کی وہ پہلے بھی ترغیب دیا کرتے تھے.وہ پہلے بھی یہی کہا کرتے تھے کہ خدا ایک ہے اور وہی انسانوں کا مددگار ہے.اسی پر بنی نوع انسان کو توکل رکھنا چاہیے.اور اسی سے اپنی حاجات مانگنی چاۂیں.وہ پہلے بھی یہی کہا کرتے تھے کہ کفر بری چیز ہے اور اسلام سچا مذہب ہے.پس کون سی وہ زائد بات تھی جس پر مکہ والوں کو جوش آ سکتا تھا یا انہیں جوش میں آنا چاہیے تھا.یقیناً جہاں تک اعتقادات کا سوال ہے مسلمانوں میں کوئی زائد چیز ایسی پیدا نہیں ہوئی جس پر ان کو تین سال کے بعد غصہ پیدا ہوا.اور انہوں نے مسلمانوں کو مبتلائے آلام کرنا شروع کر دیا.پس تین سال کے بعد اللہ تعالیٰ کا مسلمانوں کو مخالفت کی خبر دینا اس لئے نہیں تھا کہ مسلمانوں کے مذہب یا ان کے اعتقادات کا کفّار مکہ کو پہلے علم نہیں تھا.بلکہ اس لئے تھا کہ اب مسلمانوں کو ایسی ترقی حاصل ہو رہی تھی.کہ کفار یہ سمجھنے لگ گئے تھے کہ اب ہمارے لئے یہ ایک مستقل خطرہ پیدا ہو گیا ہے اور اس کا ازالہ ضروری ہے.مگر سوال یہ ہے کہ مسلمانوں کو ایسی طاقت دے دینا جس سے کفار کو اپنے لئے حقیقی خطرہ نظر آنے لگ گیا.یہ کس کا کام تھا.اس کا جواب سوائے اس کے کچھ نہیں کہ یہ خدا تعالیٰ کا کام تھا کسی انسان کا کام نہیں تھا.پس کفار مکہ کی مخالفت کی خبر دینا کوئی قیاسی امر نہیں تھا بلکہ ایک آسمانی خبر تھی جو علم غیب پر مشتمل تھی اور جس کی صداقت کی انہوں نے اپنے اعمال سے تصدیق کر دی.
Page 314
دوسرے معنوں کے رو سے شہادت یہ ہو گی کہ تو اس میں ہر تیر کا نشانہ بنے گا.اب یہ ایک مبالغہ آمیز امر نہیں.بلکہ جیسا کہ میں نے بتایا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر قسم کے ظلم ہوئے (۱) آپ کو عبادت سے روکا گیا (۲)مارا پیٹا گیا (۳)گالیاں دی گئیں (۴)تعلقات باہمی سے روکا گیا (۵) غذا سے روکا گیا (۶) تبلیغ سے روکا گیا (۷)صحابہؓ کو پتھروں پر گھسیٹا گیا (۸)ہجرت سے روکا گیا.لوگ مارتے ہیں تو کہتے ہیں نکل جاؤ.مگر یہاں مارتے بھی تھے اور نکلنے بھی نہیں دیتے تھے.چنانچہ بعض صحابہ جب ان مظالم سے تنگ آ کر چوری چھپے حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے تو مکہ کے بعض بڑے بڑے رؤسا نجاشی کے پاس پہنچے اور اسے کہا کہ یہ ہمارے غلام ہیں جو ہمارے ملک سے بھاگ کر یہاں آ گئے ہیں.ان کو واپس کیا جائے گویا ان کی سکیم یہی تھی کہ ہم مسلمانوں کو نہ مکہ میں آرام سے رہنے دیں گے اور نہ ان کو باہر جانے دیں گے.(۹)عورتوں کو شرمناک طریقوں سے مارا گیا (۱۰) جھوٹے الزامات لگائے گئے کبھی پاگل کہا گیا، کبھی خود غرض کہا گیا، کبھی جھوٹا کہا گیا، کبھی عزت کا متلاشی کہا گیا، کبھی کاہن اور کبھی دوسری کتب سے چرا کر مضمون بنانے والا کہا گیا غرض کوئی تیر نہ تھا جو مکہ والوں نے آپ پر نہ چلایا ہو.تیسرے معنے یہ تھے کہ تو اس شہر میں سے جا کر پھر اترنے والا ہے.یعنی یہ شہر دو۲ زبردست ثبوت اسلام کی صداقت کے پیش کرے گا.اوّل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم کی ہجرت کا اور پھر آپ کے واپس آنے کا کہ دونوں اپنی اپنی جگہ محال تھے.مکہ والے اس سورۃ کے نزول کے وقت میں یا آپ کو ناقابل التفات سمجھتے تھے.یا آپ کو ایک قابل احترام وجود سمجھتے تھے.دونوں حالتوں میں آپ کے اخراج کا کوئی خیال بھی نہیں کر سکتا تھا.خود رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم کو اپنا نکالا جانا اس قدر ناممکن نظر آتا تھا کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم کو پہلا الہام ہوا.اور آپ گھبراہٹ اور اضطراب کی حالت میں گھر تشریف لائے تو آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے اس واقعہ کا ذکر کیا.وہ آ پ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں جو ان کے چچا زاد بھائی اور بائیبل کے بہت بڑے عالم تھے اور ان سے ان الہامات کا ذکر کیا.ورقہ بن نوفل نے خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی حالات دریافت کئے.اور آپ نے وہ تمام واقعہ تفصیل کے ساتھ سنایا جو غارِ حرا میں آپ کے ساتھ گذرا تھا.ورقہ بن نوفل آپ کی گفتگو سننے کے بعد کہنے لگے.اس پر تو وہی فرشتہ نازل ہوا ہے جو موسیٰ پر نازل ہوا تھا.اس جگہ ضمنی طور پر یہ امر قابل ذکر ہے کہ ورقہ بن نوفل عیسائی تھے اور وہ صحف مقدسہ کا اکثر مطالعہ رکھا کرتے تھے.اگر وہ حضرت عیسٰی علیہ السلام کو بھی کسی ویسی ہی شریعت کا بانی سمجھتے جس قسم کی شریعت کے بانی حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے تو وہ قطعاً یہ نہ کہتے کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا.بلکہ
Page 315
وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیتے اور کہتے یہ وہ فرشتہ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا یا یہ کہتے کہ تم پر تو کوئی فرشتہ نازل ہی نہیں ہو سکتا.حضرت عیسٰی علیہ السلام آ چکے اور وہی دنیا کے آخری نجات دہندہ تھے.اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا مگر وہ سنتے ہیں تو یہ کہتے ہیں.ھَذَا النَّامُوْسَ الَّذِیْ اُنْزِلَ عَلٰی مُوْسٰی یعنی یہ تو وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ نبی پر وحئ آسمانی لایا تھا.پھر انہوں نے کہا لَوْ کُنْتُ جَذَعًا اِذْیُـخْرِجُکَ قَوْمُکَ کاش میں اس وقت قوی اور طاقتور ہوتا جب تیری قوم تجھ کو مکہ میں سے نکال دے گی.اگر مجھ میں ہمت اور طاقت رہی.اور اگر میں اس وقت زندہ ہوا تو اَنْصُـرْکَ نَصْـرًا مُؤَذَّرًا میں اپنی پوری ہمت اور اپنی پوری طاقت کے ساتھ تیری مدد کروں گا.ورقہ بن نوفل کی یہ بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کے لئے اتنی عجیب تھی کہ آپ اس کو سن کر حیران رہ گئے.چنانچہ باوجود اس کے کہ آپ کو الہام ہو چکا تھا آپ نے حیرت سے کہا اَوَ مُـخْرِجِیَّ ھُمْ کیا مکہ کے لوگ مجھ کو نکال دیں گے.یعنی میرے جیسا پرامن اور صلح پسند انسان جو ہر قسم کے حقوق کو ادا کرنے والا ہے.اسے مکہ کے لوگ کس طرح نکال سکتے ہیں.میری ان سے کوئی دشمنی نہیں.میں ان کا کبھی بد خواہ نہیں ہوا.میری ان سے کوئی لڑائی نہیں ہوئی.پھر اسی مکہ میں میرے رشتہ دار اور دوست موجود ہیں.ان سب باتوں کے ہوتے ہوئے یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے مکہ میں سے نکال دیں.دنیامیں لوگ اگر کسی کو نکالتے ہیں تو دشمنی کی وجہ سے مگر میری تو کسی سے دشمنی نہیں ہے.کیا میرے جیسے پرامن کو بھی یہ لوگ نکال دیں گے.اور اگر نکالیں گے تو کیا جرم ہوگا اور کون سا قصور ہوگا جس کی وجہ سے میں اس مکہ میں سے نکالا جاؤں گا.کتنے مختصر مگر کتنے گہرے معانی رکھنے والے وہ الفاظ ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم نے اس موقعہ پر استعمال فرمائے.اَوَ مُـخْرِجِیَّ ھُمْ بظاہر ایک چھوٹا سا فقرہ ہے مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم کی قلبی کیفیات کی ایک وسیع دنیا ان الفاظ میں آباد ہے.اگر ایک طرف ان الفاظ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کس قدر صلح اور آشتی اور محبت کے جذبات سے لبریز تھا.تو دوسری طرف ان الفاظ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم کا وجود خود مکہ والوں کی نگاہ میں اس قدر محبوب تھا کہ ظاہری حالات کے لحاظ سے یہ بالکل ناممکن نظر آتا تھا کہ وہ آپ جیسے انسان کو مکہ میں سے نکال سکیں گے.مگر پھر ہوا یہی کہ انہوں نے باوجود آپ کی صلح پسندی کے اور باوجود آپ کے پُر امن ہونے کے آپ کو مکہ میں سے نکال دیا اور خدا کی بات پوری ہوئی.لوگ کہتے ہیں کہ مخالف حالات کو دیکھ کر بعض دفعہ قبل از وقت ایک رائے کا اظہار کر دیا جاتا ہے اور اس کا نام پیشگوئی رکھ لیا جاتا ہے.میں ایسے لوگوں سے کہتا ہوں وہ اس پیشگوئی پر غور کریں اور سوچیں کہ کیا عالم الغیب خدا کے سوا
Page 316
کوئی انسان اپنی طرف سے یہ بات کہہ سکتا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم کو ایک دن مکہ میں سے ہجرت کرنی پڑے گی.اور لوگوں کو تو جانے دو، خود رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم نہیں سمجھتے تھے اور آپ حیران ہوتے تھے کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ میں مکہ میں سے نکالا جاؤں.اور جس امر کو آپ نہ سمجھتے تھے اسے کوئی دوسرا کیا سمجھ سکتا تھا.مگر باوجود اس کے کہ آپ کی اپنی نگاہ میں یہ بات ناممکن تھی مگر مکہ والوں کے حالات کے لحاظ سے یہ بات ناممکن نظر آتی تھی.پھر بھی خدا کی بات پوری ہوئی.اور رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم کو ایک لمبے عرصہ کے شدید مظالم کے نتیجہ میں مکہ سے ہجرت کرنی پڑی.اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم کا مکہ میں واپس آنا کیسا ناممکن نظر آتا تھا.جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو چھوڑ کر چلے گئے تھے.اس وقت کون شخص خیال بھی کر سکتا تھا کہ رات کی تاریکی میں مکہ سے دو۲ بھاگنے والے ایک دن دس ہزار کا لشکر جرار اپنے ساتھ لئے فاتحانہ حیثیت سے مکہ میں داخل ہوں گے.اور مکہ کے بڑے بڑے سردارمسلمانوں کے رحم وکرم پر ہوں گے کہ وہ جیسا چاہیں ان سے سلوک کریں.اس وقت کون ان باتوں کو اپنے وہم و گمان میں بھی لا سکتا تھا.اور کون کہہ سکتا تھا کہ وہ کفار جو آج خوش ہو رہے ہیں جو اس خیال سے پھولے نہیں سماتے کہ وہ اسلام کی شوکت کو مٹانے میں کامیاب ہو گئے ہیں.ان کی آنکھوں کے سامنے صرف چند سال کے عرصہ کے اندر اندر وہی شخص جسے مکہ سے نکالا گیا تھا دس ہزار قدوسیوں کے ساتھ مکہ میں واپس آئے گا.اور بڑے جاہ و جلال کے ساتھ فرمائے گا کہ اے مکہ والو! بتاؤ اب میں تم سے کیا سلوک کروں.اور وہ یہ جواب دیں گے کہ وہی سلوک کریں جو یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا.ہجرت کے وقت زیادہ سے زیادہ بعض لوگوں کے دلوں میں یہ خیال پیدا ہوتا ہو گا کہ افسوس ہم آپ کو مار نہ سکے.اور بعض لوگ یہ کہتے ہوں گے کہ چلو اچھا ہوا خس کم جہاں پاک (نعوذ باللہ من ذالک) ہماری نگاہوں سے تو وہ اوجھل ہوا.اب ہمیں اس سے کیا غرض کہ وہ زندہ ہے یا نہیں.ہم نے اسے اپنے شہر سے تو نکال دیا.اس وقت کون خیال کر سکتا تھا کہ وہی لوگ جو آج یہ کہہ رہے ہیں کہ چلو اچھا ہوا ہمیں چھٹی مل گئی ایک بلا اور مصیبت سے چھٹکارا ہوا.انہی لوگوں میں وہ ایک فاتح جرنیل کی حیثیت میں واپس آئے گا.اور پھر کون یہ خیال بھی کر سکتا تھا کہ وہ اتنی جلدی واپس آئے گا کہ لوگوں کے لئے نہ صرف اس کی واپسی بلکہ اس قدر جلد واپسی حیرت انگیز ہو گی.واقعہ میں اگر غور کیا جائے تو یہ ایک ایسا عظیم الشان نشان ہے جس سے خدا تعالیٰ کی ہستی اور اس کی طاقت و جبروت کا نقشہ انسانی آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے.مکہ سے رات کی تاریکی میں دو۲ بھاگنے والے بھاگے اور اس حالت میں بھاگے کہ انہیں اپنی جان خطرہ میں گھری ہوئی دکھائی دے
Page 317
رہی تھی اور کفار نے یہ ارادہ کیا ہوا تھا کہ ان کو زندہ نہ چھوڑا جائے.مگر پھر آٹھ سال کے بعد اسی مکہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم ایک فاتح کی حیثیت میں واپس آئے.آٹھ سال میں تو ایک ڈاکو بھی پوری طرح تیار نہیں ہوتا.مگر یہاں یہ خبر دی گئی تھی کہ آٹھ سال کے اندر محمدر سول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم جو صرف ایک ساتھی کے ساتھ مکہ سے رات کے وقت بھاگے تھے اور جن کو زندہ یا مردہ پکڑلانے پر انعام مقررتھا.وہ آٹھویں سال مکہ میں داخل ہوں گے ایک فاتح جرنیل کی حیثیت میں داخل ہوں گے اور ایسی حالت میں داخل ہوں گے کہ قیدار کی ساری حشمت تباہ ہو چکی ہو گی.چنانچہ ایسا ہی ہوا.اور آپ اللہ تعالیٰ کی تائید اور اس کی نصرت کے ساتھ اسلام کی فتح کا جھنڈا اڑاتے ہوئے مکہ میں داخل ہوئے اور یہ پیشگوئی بڑی شان کے ساتھ پوری ہوئی کہ اَنْتَ حِلٌّۢ بِهٰذَا الْبَلَدِ (اَشْھَدُ اَنْ لَّاۤاِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ وَاَشْھَدُ اَنَّ مُـحَمَّدًا عَبْدُہٗ وَرَسُوْلُہٗ) دیکھو یہاں کس طرح ابتدائی زمانہ میں ہی فجر کے معنی بھی کر دئیے یعنی ہجرت اور ایک ہی وقت میں دوسری کامل فجر جو بدر سے شروع ہوئی اور فتح مکہ پر مکمل ہوئی.اس کا بھی ذکر کر دیا کہ دوسرا ثبوت مکہ ہماری باتوں کی درستی کا اس طرح دے گا کہ تو اس شہر میں پھر نازل ہو گا اور پھر اللہ تعالیٰ کا جلال اور اس کی قدرت کا ایک عظیم الشان نشان تیرے ذریعہ سے مکہ میں نظر آنے لگ جائے گا.پھر اللہ تعالیٰ اس بات کو شہادت کے طور پر پیش کرتا ہے کہ یہ مکہ ایک لمبے عرصہ سے محفوظ چلا آتا تھا.جب لوگ بت پرست اور دین سے غافل تھے.اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے ابرہہ سے اس کی حفاظت کی.مگر اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم کے ہاتھوں سے قہراً فتح ہو گا.اور نہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم کا داخلہ آپ کی سچائی کا ثبوت ہو گا بلکہ قہراً داخلہ دوسری دلیل مہیا کرے گا کہ اگر خدا تعالیٰ ان کے ساتھ نہیں تو ان کو مکہ میں قہراً داخل ہونے کی اس نے کیوں اجازت دی.گویا علاوہ داخلہ کی پیشگوئی کے پورا ہونے کے یہ مزید دلیل ہو گی اس ا مر کی کہ آپ سچے ہیں جو بات ابرہہ کو نصیب نہ ہوئی.وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم کو نصیب ہوگئی.ابرہہ آیا تو خدا تعالیٰ نے اسے اپنے عظیم الشان لشکر سمیت تباہ کر دیا اور اسے مکہ میں داخل نہ ہونے دیا.لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دس ہزار کا لشکر لے کر مکہ کی طرف آئے تو خدا نے آپ کو اپنے لشکر سمیت مکہ میں داخل کردیا.یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم کا نہ صرف مکہ میں داخلہ ایک پیشگوئی کوپورا کرنے والا ہے بلکہ آپ کا تلوار کے زور سے مکہ میں داخل ہونا ایک دوسری پیشگوئی کو پورا کرنے والا ہے.اگر بالفرض مکہ والے آپ سے کہتے کہ آپ اپنے شہر میں واپس آ جائیں اور آپ واپس آ جاتے تو اس سے صرف ایک پیشگوئی
Page 318
پوری ہوتی.مگر آپ کا داخلہ دو پیشگوئیوں کو پورا کرنے کا موجب بنا.یعنی نہ صرف آپ مکہ میں داخل ہو ئے بلکہ الٰہی پیشگوئی کے مطابق مکہ کی حرمت کو توڑتے ہوئے اس میں داخل ہوئے دنیا کی گذشتہ ۲۵سو سال کی تاریخ میں کوئی ایک مثال بھی ایسی نہیں ملتی کہ کوئی شخص تلوار کے زور سے مکہ کو فتح کرنے میں کامیاب ہوا ہو.ابرہہ آیا اور اس نے تلوار کے زور سے مکہ میں داخل ہونا چاہا مگر خدا نے اسے تباہ کر دیا.لیکن فرماتا ہے اَنْتَ حِلٌّۢ بِهٰذَا الْبَلَدِ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے لئے اس شہر کو حلال کر دیا جائے گا اور تیرے ذریعہ اس شہر کو تلوار کے زور سے فتح کیا جائے گا.مکہ والوں کا یقین ہے کہ کوئی شخص تلوار کے زور سے اس شہر کو فتح نہیں کر سکتا.مگر ہمارا تجھ سے نہ صرف یہ وعدہ ہے کہ ہم تجھے واپس لائیں گے بلکہ یہ بھی وعدہ ہے کہ ہم تلوار کے زور سے واپس لائیں گے تا کہ مکہ والوں کا جو یہ عقیدہ ہے کہ کوئی شخص تلوار سے مکہ کو فتح نہیں کر سکتا وہ تیرے ذریعہ سے باطل کر دیا جائے.مگر نہ اس لئے کہ مکہ کو حفاظت حاصل نہیں بلکہ اس لئے کہ جس نے مکہ کی حفاظت کی تھی وہ بھی میں تھا اور جو تلوار کے زور سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شہر میں لایا وہ بھی میں ہی ہوں.پانچویں یہ بتایا کہ اس شہر کو ہم اوپر کی باتوں کے لئے بطور شہادت پیش کرتے ہیں.جب کہ تو اس شہر کی بنیاد کا مقصود ہے یعنی ایسی حالت میں کہ مکہ کا مقصود تو ہے.ہم اسے شہادت کے طور پر پیش کرتے ہیں.اور دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب کہ شروع دن سے ظہور محمدی مکہ مکرمہ کے قیام کا موجب تھا.تو اب یہ لوگ کس طرح خیال کر سکتے ہیں کہ صدیوں سے ایک مقصد کی طرف دنیا کو لاتے ہوئے عین جب اس مقصد کے پورا کرنے کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ اسے بھلا دے گا اور اس مقصود کا ساتھ چھوڑ دے گا.اگر خدا نے اس وقت مکہ کو لوگوں کا مرجع بنا دیا جب مکہ کا تاج اس کے سر پر نہیں تھا.اگر خدا نے اس وقت مکہ کو ہر طرف سے رزق مہیا کیا جب مکہ کا تاج اس کے سر پر نہیں تھا.اگر خدا نے اس وقت مکہ کو بڑا شہر بنایا جب مکہ کا تاج اس کے سر پر نہیں تھا اور اگر خدا نے اس وقت مکہ کو ہر قسم کی لڑائیوں سے محفوظ رکھا.جب مکہ کا تاج اس کے سر پر نہیں تھا.تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو جو مکہ کا مقصود اور سرتاج ہے تیرے آنے کے بعد اب یہ نشانات کس طرح مٹ سکتے ہیں.یہ نشانات اور بھی ظاہر ہوں گے اور آئندہ رونما ہونے والی پیشگوئیاں نہ صرف تیری صداقت کا ایک زندہ نشان ہوں گی.بلکہ خود مکہ ان پیشگوئیوں کے ذریعہ اور زیادہ عزت پائے گا.اور خدا تعالیٰ کے کلام کے لئے دنیا کے سامنے ایک زبردست شہادت مہیا کرے گا.کیونکہ تو مقصود ہے مکہ کا، تو سرتاج ہے مکہ کا اور تیری طرف ہی ہزارہا سال کے تاریخی واقعات کی انگلی اشارہ کر
Page 319
رہی تھی.اب تیرے آنے کے بعد خدا تعالیٰ کے نشانات کا ایسا ظہور ہو گا جو دنیا میں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا.غرض ایک مختصر سے فقرہ میں اللہ تعالیٰ نے لیالی عشـر کی بھی تشریح کر دی لیالی عشـر کے بعد ظاہر ہونے والی پہلی فجر کی بھی تشریح کر دی.اور پھر اس دوسری فجر کی بھی تشریح کر دی جو گیارہویں رات کے اختتام پر جنگ بدر سے شروع ہوئی اور جس کا انتہا فتح مکہ پر ہوا.ان لوگوں کے لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم اور آپ کے صحابہؓ کا مکہ کی فتح کے لئے آنا کتنی حیرت و استعجاب کی بات تھی.اس کا کچھ اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ مکہ کے لوگ اس امید میں بیٹھے تھے کہ ابو سفیان محمد صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم سے ایک نیا معاہدہ کر کے آ رہا ہے.وہ رات کو اس امید میں سوئے کہ ابوسفیان ہمارے لئے امن کا پیغام لا رہا ہے.مگر آدھی رات کے وقت جب کہ وہ میٹھی نیند سو رہے تھے.ابوسفیان گھوڑا دوڑاتے ہوئے مکہ میں داخل ہوا.اور بلند آواز سے پکارنا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم دس ہزار صحابہ سمیت مکہ کی طرف بڑھتے چلے آرہے ہیں.مگر میں ان سے یہ رعائت لے کر آیا ہوں کہ جو شخص اپنے گھر کے دروازے بند کرلے گا.اور ان کے مقابلہ کے لئے باہر نہیں نکلے گا اسے کچھ نہیں کہا جائے گا.لیکن جو شخص گلیوں میں پھرے گا یا تلوار لے کر مقابلہ کے لئے کھڑا ہو گا وہ اپنی جان کا آپ ذمہ دار ہوگا.(السیرۃ النبویۃ لابن ھشام زیر عنوان ’’اسلام ابی سفیان بن الـحارث و عبد اللہ بن امیۃ‘‘) اب کجا تو یہ حالت تھی کہ وہ مکہ والوں کی طرف سے صلح کا سفیر بن کر گیا تھا.اور کجا یہ حالت ہے کہ جب وہ واپس آیا تو ایسی حالت میں کہ اس نے اپنی قوم سے کہا.محمد صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم کا لشکر فاتحانہ طور پر مکہ میں داخل ہو رہا ہے.میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ تمہارے لئے میں بعض مراعات لے کر آیا ہوں اور پھر اس نے ان مراعات کا ان الفا ظ میں اعلان کیا کہ جو شخص اپنے گھر کے دروازے بند کر کے بیٹھ رہے گا.اس کی جان بخشی کی جائے گی لیکن اگر کوئی باہر نکلا یا اس نے مسلمانوں کا مقابلہ کیا تو وہ اپنی جان کا آپ ذمہ وار ہو گا.چنانچہ ایک طرف سے خالدؓ اپنی فوجوں سمیت مکہ میں داخل ہوئے.دوسری طرف سے زبیر اور سعد بن عبادہ اپنے دستے لے کر بڑھے اور تیسری طرف سے محمد صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم بغیر کسی لشکر کے بغیر کسی جاہ وحشم کے اکیلے مکہ میں داخل ہوئے.آپ کا اکیلے مکہ میں داخل ہونا کوئی معمولی بات نہیں تھی.مکہ والے جانتے تھے کہ یہ اکیلا داخلہ لشکر سمیت داخلہ سے ہزارہا گنا زیادہ شاندار ہے.کیونکہ گو آپ اکیلے تھے مگر زبانِ حال سے مکہ والوں کو کہہ رہے تھے.کہ دیکھو گو میں لشکر کے بغیر مکہ میں داخل ہو رہا
Page 320
ہوں.مگر آج مجھے نظر بد سے دیکھنے کی تم میں جرأت نہیں ہے.میرے دائیں اور بائیں خدا تعالیٰ کے فرشتے حفاظت کے لئے کھڑے ہیں اور میں توبہ کا پیغام لے کر تمہاری طرف آ رہا ہوں.اب چاہو تو توبہ کو قبول کر کے خدا تعالیٰ کی فوج میں شامل ہو جاؤ اور چاہو تو ان فرشتوں کی تلوار کا شکار ہو جاؤ جو دائیں طرف سے بھی مکہ میں داخل ہو رہے ہیں اور بائیں طرف سے بھی مکہ میں داخل ہو رہے ہیں.وَ وَالِدٍ وَّ مَا وَلَدَۙ۰۰۴ اور باپ کی بھی اور بیٹے کی بھی (قسم کھاتا ہوں) تفسیر.حضرت ابن عباسؓ نے کہا ہے کہ وَالِدٍ وَّمَاوَلَدَ سے مراد سب جاندار ہیں.یعنی میں اس بلد کو بھی پیش کرتا ہوں اور تمام جانداروں کو بھی بطور شہادت پیش کرتا ہوں.مجاہد کہتے ہیں کہ اس سے مراد آدم اور ان کی ساری اولاد ہے یعنی میں اس بلد کو بھی پیش کرتا ہوں اور میں تمام دنیا کے باپ اور اس کی اولاد یعنی تمام بنی نوع انسان کو بھی بطور ثبوت پیش کرتا ہوں.بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد تمام صلحاء اور ان کی اولادیں ہیں.یعنی میں اس بلد الحرام کو بھی جس کا مقصود تو ہے یا جس میں تو ہر تیر کا نشانہ بننے والا ہے یا جس میں تو اترنے والا ہے یا جسے تیرے لئے حلال کیا جانے والا ہے اس کو بھی بطور شہادت پیش کرتا ہوں.اور تمام صلحاء اور ان کی اولادوں کو بھی بطور شہادت پیش کرتا ہوں.بعض کہتے ہیں کہ اس سے نوح اور ان کی اولاد مراد ہے.ابو عمران الحوفی کہتے ہیں کہ اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی سب اولاد مراد ہے.طبری اور ماوردی کا قول ہے کہ وَالِد سے مراد رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم ہیں اور مَاوَلَدَ سے مراد آپ کی امت ہے کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم فرماتے ہیں اَنَا لَکُمْ بِـمَنْـزِلَۃِ الْوَالِدِ میرا تعلق تم سے ایسا ہی ہے جیسے باپ کا اپنی اولاد سے ہوتا ہے.اسی طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاَزْوَاجُهٗۤ اُمَّهٰتُهُمْ (الاحزاب:۷) رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں.جب وہ مائیں ہوئیں تو وہ شخص جس کے تعلق کی وجہ سے وہ ہماری مائیں بنی ہیں بدرجہ اولیٰ ہمارا باپ ہوا.پس قرآن کریم نے بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم کو والد قرار دیا ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم خود بھی فرماتے ہیں کہ اَنَا لَکُمْ بِـمَنْـزِلَۃِ الْوَالِدِ میرا تعلق تم سے ایسا ہی ہے جیسے باپ کا اپنی اولاد سے ہوتا ہے(التفسیر البحر المحیط زیر آیت ’’وَ وَالِدٍ وَّ مَا وَلَدَ‘‘).
Page 321
بحر محیط والے لکھتے ہیں کہ آپ کے مقام کی قسم کھانے کے بعد آپ کی اور آپ کی امت کی قسم اظہار شرف کے لئے کھائی گئی ہے٭ میں قسم کے بارے میںبار بار بتا چکا ہوں کہ قسم سے مراد محض شہادت ہوتی ہے اور غرض اس کی یہ ہوتی ہے کہ ان چیزوں کو ان مخصوص حالات میں یا عام حالات میں ہم بطور شہادت پیش کرتے ہیں.بعض دفعہ عام حالات مراد ہوتے ہیں اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان چیزوں کے حالات سے جو سبق ملتا ہے اسے ہم بطور شہادت پیش کرتے ہیں کہ ہمارا دعویٰ صحیح ہے لیکن کبھی ان چیزوں کے مخصوص حالات مراد ہوتے ہیں.جیسے یہاں فرمایا کہ ہم اس مکہ کو بطور شہادت تو پیش کرتے ہیں مگر ایسے حال میں کہ اَنْتَ حِلٌّۢ بِهٰذَا الْبَلَدِ یہ کہنا کہ قسم اکرام کے لئے کھائی گئی ہے یہ بالکل عبث بات ہے.دنیا میں کبھی کوئی شخص عزت کے لئے قسم نہیں کھاتا.کیا یہ بھی کوئی کہا کرتا ہے کہ چونکہ میرے دل میں تمہاری عزت ہے اس لئے میں تمہاری قسم کھاتا ہوں.یہ نہ عربی کا محاورہ ہے اور نہ کسی اور زبان کا.صرف اس لئے کہ مفسرین کی سمجھ میں قسم کی حقیقت نہیں آئی.انہوں نے یہ کہہ دیا کہ قسم اکرام کے لئے کھائی گئی ہے.اس میں کوئی شبہ نہیں کہ قرآن کریم میں جس کا بھی ذکر آئے گا خواہ وہ ذکر کسی شہادت کے لئے آئے یا کسی کی نیکیوں کی یادگار کے طور پر آئے.اس کا اکرام ہو جائے گا مگر یہ ایک ضمنی بات ہے قسم اکرام کے لئے نہیں کھائی جاتی.ہاں جب قسم کھائی جاتی ہے تو اگر وہ اچھی بات کے لئے ہو تو اس چیز کا اکرام بھی ہو جاتا ہے.مگر مقصد اکرام نہیں ہوتا.اکرام اس کا ایک طبعی نتیجہ ہوتا ہے.وَوَالِدٍ وَّمَاوَلَدَ کا صحیح مفہوم میرے نزدیک وَالِدٍ وَّمَاوَلَدَ کے معنی (اوّل) حضرت ابراہیم اور حضرت اسمٰعیل علیہما السلام کے ہیں.قرآن کریم سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ خانہ کعبہ اور مکہ مکرمہ کا تعلق خصوصیت کے ساتھ حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے حضرت اسمٰعیل علیہما السلام کے ساتھ ہے.اور جب ایک چیز کو بغیر تعیین کے بیان کیا گیا ہو تو لازماً سب سے مقدم حق انہی وجودوں کا ہے جن کا تعلق اس مضمون سے ہو جو وہاں بیان ہو رہا ہو.چونکہ وَالِدٍ وَّمَاوَلَدَ سے پہلے ذکر مکہ مکرمہ کا ہے.اس لئے لازمًا ہمیں ایسے ہی وَالِد اور مَوْلُوْد کی تلاش کرنی ہوگی جن کا مکہ سے خاص تعلق ہو.اب ہمیں خود قرآن کریم سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی، حضرت اسمٰعیل علیہ السلام کو مکہ میں لا کر بسایا اور خدا تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ اسے ایک شہر بنادے.یہاں دور دور سے لوگ کھچے چلے آئیں.ان کو رزق میسر آئے.پھر یہ شہر امن والا ہو اور خدا تعالیٰ کا ذکر کرنےو الے اور اس کے نام پر اپنی زندگیاں قربان کرنے والے اس شہر میں پیدا ہوں.یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام
Page 322
نے کی اور حضرت اسمٰعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر کی.پھر حضرت اسمٰعیل علیہ السلام کے جوان ہونے سے پہلے جب وہ ابھی بچے ہی تھے ان کو مکہ مکرمہ میں لا کر چھوڑ دیا.اور ایسی حالت میں چھوڑا جبکہ وہاں کھانے پینے کا کوئی سامان نہ تھا.محض خدا تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے اور اس کے وعدوں پر یقین رکھتے ہوئے انہوں نے حضرت اسمٰعیل علیہ السلام کو ایک بے آب وگیاہ وادی میں لا کر بسا دیا.پس اگر کوئی وَالِد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کے زمانۂ بعثت سے پہلے کا مکہ سے تعلق رکھنے والوںمیں سے لوگوں کے ذہن میں آ سکتا ہے تو وہ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں.اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانۂ بعثت سے پہلے اگر کسی ولد کی طرف انسانی ذہن منتقل ہو سکتا ہے تو وہ حضرت اسمٰعیل علیہ السلام ہیں.یہ ایک ایسا کھلا اور بیّن امر ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن مجید کا منکر ہو تو وہ بھی اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اگر کوئی باپ اور بیٹا مکہ مکرمہ سے خاص طور پر تعلق رکھتے تھے تو وہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسمٰعیل علیہما السلام ہی تھے اور جب یہ ایسی نمایاں بات ہے تو جس باپ اور بیٹے کا یہاں ذکر ہے ان کی تعیین کرنے میں ہمارے لئے کیا مشکل ہے.جب بغیر کسی تعیین کے ایک لفظ بولا جاتا ہے تو اس کے دو ہی مفہوم ہوتے ہیں یا تو وہ کلّی طور پر عام ہوتا ہے اور یا اتنا نمایاں ہوتا ہے کہ اس کے لئے کسی تعیین کی ضرورت ہی نہیں ہوتی.مثلاً جب ہم دن کا لفظ استعمال کریں گے تو اس سے یا تو ہر دن مراد ہو گا اور یا ایسا دن مرا دہو گا جو ہماری زندگیوں پر ایسا نمایاں اثر رکھتا ہو کہ خود بخود انسانی ذہن اس دن کی طرف چلا جاتا ہو.ہر فصیح زبان میں یہی طریق رائج ہے کہ جب نکرہ استعمال کیا جائے یا تو اس سے مراد وہ تمام افراد ہوں گے جو اس میں آ سکتے ہوں اور یا ان افراد میں سے وہ خاص وجود جو اتنا خاص ہو کہ اس کے لئے کسی تعیین کی ضرورت نہ ہو.اس کے لئے نکرہ آئے گا.اس کے خلاف کوئی اور معنی کرنے کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہوسکتے.ہمارے ملک کی عورتیں تک جب اپنی زندگی کے خاص دن کا ذکر کریں تو بغیر تعیین کے کہہ دیتی ہیں.او دن نہیں بھلدا.یعنی وہ دن نہیں بھولتا.اور مراد یہی ہوتی ہے کہ وہ دن میری زندگی میں اتنا اہم ہے کہ میرے سب جاننے والے صرف اشارہ سے اسے سمجھ سکتے ہیں.پس میرے نزدیک وَالِدٍ وَّمَاوَلَدَ کے یہ معنی کرنے کے اس سے صلحاء اور ان کی اولاد مراد ہے.یا نوح اور ان کی اولاد مراد ہے.یہ سب عقل کے خلاف معنے ہیں.اور ایک نکرہ کا وجود ان کی برداشت نہیں کر سکتا.لیکن جہاں تک حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے کا تعلق ہے (میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری اولاد مراد نہیں لیتا.بلکہ مَاوَلَدَ سے صرف حضرت اسمٰعیل علیہ السلام مراد لیتا ہوں) اس حد تک کوئی شخص اس حقیقت سے
Page 323
انکار نہیں کر سکتا کہ مکہ کی بنیاد انہوں نے رکھی.پس جنہوں نے مکہ کو بنایا ہے جنہوں نے خانہ کعبہ کی بنیادوں کو استوار کیا ہے اگر ہم ان کا نام نہیں لیتے اور بغیر تعیین کے مکہ کے ذکر میں باپ بیٹے کے الفاظ سے ان کا ذکر کر دیتے ہیں تو ہرعقل مند انسان سوائے ابراہیمؑ اور اسمٰعیل کے کسی اور شخص کا نام اپنے ذہن میں لا ہی نہیں سکتا.ہمارے ملک میں عام لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ ’’او مدینے والیا‘‘ اب جہاں تک مدینے میں رہنے والوں کا سوال ہے.اس میں لاکھوں بلکہ کروڑوں لوگ اس وقت تک بس چکے ہیں.اور ان الفاظ سے یہ تعیین نہیں ہوتی کہ کہنے والے نے کس کا ذکر کیا ہے.آیا اس سے مدینہ کا ہر شخص مراد ہے یا مدینہ کا کوئی خاص شخص مراد ہے.مگر باوجود اس کے کہ الفاظ میں کسی کی تعیین نہیں ہوتی جب کوئی شخص یہ الفاظ استعمال کرتا ہے کہ ’’او مدینے والیا‘‘ ’’اومدینے والے‘‘ تو ہر شخص کا ذہن فوری طور پر اس امر کی طرف منتقل ہو جاتا ہے کہ اس سے مراد مدینہ کا ہر شخص نہیں بلکہ اس سے مراد مدینہ کا وہ مقدس انسان ہے جس سے مدینہ کو عزت حاصل ہوئی.اب دیکھ لو یہ الفاظ ہمارے ملک میں روزانہ استعمال کئے جاتے ہیں.پنجابی شعراء جب نعت کہتے ہیں تو انہی الفاظ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم کو مخاطب کرتے ہیں.مگر کبھی ان الفاظ کے متعلق کسی شخص کے دل میں شبہ پیدا نہیں ہوتا.وہ کبھی نہیں کہتا کہ یہ تو نکرہ ہے اور اس سے مدینے کا ہر شخص مراد ہو سکتا ہے.وہ جانتا ہے کہ گو یہ نکرہ ہے مگر اس سے مراد وہ معرفہ ہے جس سے زیادہ مدینہ کے ذکر میں اور کسی کو تعیین حاصل نہیں.پس جس طرح روزانہ کہا جاتا ہے ’’او مدینے والیا‘‘ اور اس سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم کی ذات ہوتی ہے.اسی طرح مکہ کے ساتھ جب بھی ایک باپ اور بیٹے کا ذکر آئے گا لازماً اس سے مراد حضرت ابراہیم اور حضرت اسمٰعیل علیہما السلام ہی ہوں گے اور کوئی نہیں ہو گا.پھر یہ بھی ایک غور کرنے والی بات ہے کہ یہاں باپ اور بیٹے کو ملا کر ان کو اکٹھا ذکر کرنے کے کیا معنے تھے.خالی باپ یا خالی بیٹے کا ذکر کیوں نہیں کیا گیا.اسی لئے کہ ایک باپ اور ایک بیٹا دونوں وجود ایسے تھے جنہوں نے مل کر خانہ کعبہ بنایا.اس کی تعمیر کی اور پھر ان دونوں سے آئندہ کے لئے ایک سلسلہ ہدایت قائم ہوا.وہ خالی باپ کا فعل نہیں تھا.خالی بیٹے کا فعل نہیں تھا بلکہ ایک باپ اور ایک بیٹے کا مشترکہ فعل تھا جو انہوں نے مل کر سر انجام دیا.اسی لئے قرآن کریم نے صرف باپ یا صرف بیٹے کا ذکر نہیں کیا بلکہ باپ اور بیٹے دونوں کاذ کر کیا ہے.میں سمجھتا ہوں جو واقعہ اپنی تمام جزئیات کے ساتھ اس آیت پر چسپاں ہوتا ہو ہمیں تفسیر کرتے ہوئے پہلا حق اسی کو دینا چاہیے.اس لحاظ سے آیت کے یہ معنے ہوں گے کہ ہم اس شہر کو اس حالت میں کہ تو اس میں حِلٌّ ہے شہادت کے طور پر پیش کرتے ہیں.اور اسی طرح اس شہر کی بنیاد رکھنے والے ابراہیمؑ اور اسمٰعیلؑ کو بھی بطور شہادت پیش
Page 324
کرتے ہیں.کس امر کی شہادت کی؟ یا وہ دونوں کیا شہادت دیتے ہیں؟ اس کے متعلق مفسرین کہتے ہیں.کہ قسم کا جواب لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِیْ کَبَدٍ میں بیان ہوا ہے جو آگے آئے گا کہ ہم نے انسان کو کَبَدٍ میںپیدا کیا ہے.(تفسیر البحر المحیط زیر آیت ’’ لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِیْ کَبَدٍ ‘‘) میرے نزدیک یہ درست ہے.اور جہاں تک عربی زبان کا تعلق ہے.لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِیْ کَبَدٍ ایک بڑا قطعی اور یقینی جواب اس قسم کا ہے لیکن جہاں تک ساری آیات کا تعلق ہے میرے نزدیک یہ دوسرا جواب ہے.پہلا جواب وہی ہے جو پہلی سورتوں میں بیان ہوا.اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قسم سے پہلے لَا کا لفظ استعمال کیا ہے اور جب لَا کا لفظ استعمال کیا جائے تو اس کا کوئی نہ کوئی قرینہ ہونا چاہیے.اس میں کوئی شبہ نہیں کہ لَا کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ اظہار نہیں کیا کہ کس چیز کا انکار کیا گیا ہے.مگر اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ فصیح کلام میں لَا کے اظہار کے لئے ضرور کوئی قرینہ ہونا چاہیے.اور قریبی قرینہ یہی ہوتا ہے کہ ماسبق کی طرف اشارہ سمجھا جائے.پس جس کی طرف لَا کا اشارہ سمجھا جائے گا اسی کی طرف قسم کا بھی اشارہ سمجھا جائے گا.میرے نزدیک لَا اُقْسِمُ کے لحاظ سے ایک جواب قسم محذوف ہے.اور دوسرا جواب جو اس کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہے.اور جسے تائیدی طورپر پیش کیا جا سکتا ہے وہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِیْ کَبَدٍ ہے.گویا یہ جواب قسم تو ہے مگر ثانوی جواب ہے.اصل جواب نہیں.اصل جواب وہی ہے جو پہلے بیان ہو چکا ہے اور چونکہ وہ بیان ہو چکا تھا اللہ تعالیٰ نے اسے حذف کر دیا.اس لحاظ سے معنی یہ ہوں گے کہ ہم شہادت کے طور پر پیش کرتے ہیں اس شہر کو ایسی حالت میں جبکہ تو اس میں حِلٌّ ہے.اور ہم وَالد ابراہیمؑ اور وَلَدَ اسمٰعیل کو بھی اس بات کی شہادت کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ ہم نے پہلی آیتوں میں جو یہ باتیں بیان کی ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم کی سخت مخالفت ہو گی.یہاں تک کہ اسے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا جائے گا مگر آخر وہ کامیاب ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس شہر میں اس کو واپس لائے گا.یہ ساری باتیں ہو کر رہیں گی.اسی طرح یہ بھی ہماری قسم کا جواب ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِیْ کَبَدٍ ہم نے انسان کو کبد میں پیدا کیا ہے(آگے جب مضمون آئے گا تو اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے گا) پس یہ مزید عقلی دلیل ہو گی جو سابق شہادت کے لئے بطور تائیدی گواہ کے سمجھی جائے گی.لیکن اگر اسی کو جواب قسم سمجھا جائے تو پھر ہم کو یہ سمجھنا ہو گا کہ لَا نے اس دعویٰ کو ردّ کیا ہے جس کا لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِیْ کَبَدٍ سے استنباط ہوتا ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں ہم کو سہولت اور آرام سے بغیر کسی قسم کی قربانی کے ہرترقی مل جائے گی اور ہمیں کچھ کرنا نہیں پڑے گا.جیسا کہ عدم اکرام ضیف اور عدم تَحٰٓضُّوْنَ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ وغیرہ حالات سے معلوم ہوتا ہے.اللہ تعالیٰ اس بات کو رد کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ یہ بات درست نہیں کہ سہولت
Page 325
اور آرام سے قومی ترقی حاصل ہو جائے گی اور تمہیں کچھ کرنا نہیں پڑے گا اخلاقی اور مذہبی اور سیاسی ذمہ داریوں سے منہ موڑ کر ترقی نہیں ملتی بلکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی اس طرح کیا ہے کہ وہ محنت اور مشقت سے ترقی کرتا ہے.چنانچہ ہم اس بات کی دلیل کے طور پر مکہ کو پیش کرتے ہیں.ایسی حالت میں کہ تو اس میں حِلٌّ ہے.اور ہم ابراہیمؑ اور اسمٰعیلؑ کو بھی دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں.ان آیات کے ایک حصہ کی تشریح اوپر گذر چکی ہے اور بتایا جا چکا ہے کہ لغت کے لحاظ سے حِلٌّ کے کئی معنے ہیں.ان سب معنوں کے لحاظ سے مکہ اس بات کا ایک یقینی ثبوت ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم کو خدا تعالیٰ نے اس زمانہ کی اصلاح کے لئے مبعوث کیا ہے.اسی طرح لَیَالٍ عَشْرٍ کی تشریح کرتے ہوئے بتایا جا چکا ہے کہ مشرکین مکہ کی تکالیف کی کیا نوعیت ہو گی اور وہ کس کس رنگ میں مسلمانوں کو مبتلائے آلام کرنے کی کوشش کریں گے.یہ بات بھی بتائی جا چکی ہے کہ فجر کا ظہور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کس رنگ میں ہو گا اور کس طرح کفار کی طاقت کو توڑا جائے گا.ان تمام واقعات سے جوابِ قسم خود بخود نکل آیا کہ مکہ والوں کے ظلم اور ان کی تعدی اس بات کی متقاضی ہے کہ خدا تعالیٰ مکہ سے محمد رسول صلعم کو پہلے نکال لے جائے اور پھر فاتح کی حیثیت سے واپس لائے.اور اس طرح ثابت کرے کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم کو دنیا کی ہدایت کے لئے بھیجا ہے.وہ ہماری طرف سے ہے اور وہ ضرور جیت کر رہے گا.اب اس کے بعد فرماتا ہے وَوَالِدٍ وَّمَاوَلَدَ ہم ابراہیمؑ اور اسمٰعیلؑ کو بھی شہادت کے طور پر پیش کرتے ہیں.ان کی شہادت اس لحاظ سے ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کی بنیاد رکھتے وقت جبکہ حضرت اسمٰعیل علیہ السلام بھی ان کے ساتھ شامل تھے.یہ دعا کی تھی کہ رَبَّنَا وَ ابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَ الْحِكْمَةَ وَ يُزَكِّيْهِمْ١ؕ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ (البقرۃ:۱۳۰) گو ولد کی شہادت کا یہاں ذکر نہیں.مگر یہ صاف ظاہر ہے کہ جب وہ دونوں مل کر کام کر رہے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے تھے تو لازماً اس دعا کے وقت وہ اکیلے نہیں تھے.بلکہ حضرت اسمٰعیل علیہ السلام بھی ان کے ساتھ شامل تھے.جیسا کہ رَبَّنَا کے لفظ سے بھی ظاہر ہے.پھر اس لحاظ سے بھی یہ بات واضح ہے کہ جب انہوں نے حضرت اسمٰعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور اس موقعہ پر اللہ تعالیٰ سے بڑی بڑی دعائیں کیں.تو ان دعاؤں کے معنے یہی تھے کہ انہوں نے حضرت اسمٰعیل علیہ السلام اور ان کی اولاد کے متعلق دعائیں کی ہیں.چنانچہ وہ خود فرماتے ہیں.رَبَّنَاۤ اِنِّيْۤ اَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِيْ بِوَادٍ غَيْرِ ذِيْ زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ١ۙ رَبَّنَا لِيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ فَاجْعَلْ اَفْىِٕدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِيْۤ اِلَيْهِمْ وَ ارْزُقْهُمْ مِّنَ الثَّمَرٰتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُوْنَ
Page 326
(ابراہیم:۳۸) یعنی اے میرے رب میں نے اپنی اولاد کو ایک وادئ غیر ذی زرع میں لا کر بسایا ہے.محض اس لئے کہ وہ تیری عبادت کریں اور تیرے دین کی خدمت میں اپنی عمر بسر کر دیں تو اپنے فضل سے لوگوں کے قلوب کو ان کی طرف پھیر دے اور انہیں اپنے پاس سے رزق دے تاکہ یہ تیرے شکرگذار بندے بنیں.پس اوّل تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک رسول کی بعثت کے متعلق جو دعائیں کیں حضرت اسمٰعیل علیہ السلام ان دعاؤں میں شامل تھے.کیونکہ انہوں نے اکٹھے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی.دوسرے وہ ان دعاؤں میں اس لحاظ سے بھی شریک تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسمٰعیلؑ کی نسل سے ہی ان وعدوں کے پورا ہونے کی دعا کی تھی.یہی وجہ ہے کہ وَالِد اور وَلَد دونوں کی اکٹھی شہادت کا اللہ تعالیٰ نے اس جگہ ذکر کیا ہے اور فرمایا ہے کہ ہم اس بات کی شہادت کے طور پر کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم خدا تعالیٰ کے سچے رسول ہیں.وَالِد اور وَلَد کو تمہارے سامنے پیش کرتے ہیں.تم جانتے ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسمٰعیل کی نسل میں سے ایک رسول کی بعثت کے متعلق اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی تھیں.اگر وہ دعائیں اب تک پوری نہیں ہوئیں تو بتاؤ ابراہیم تمہارے نزدیک جھوٹا ہوا یا نہیں.پھر اسمٰعیل کی طرف دیکھو کہ اس نے ایک بہت بڑی قربانی کی.اس نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق وادئ غیر ذی زرع میں بس کر اپنی جان کو ہلاک کرنے کے لئے تیار ہوں.وہ خدا کی خاطر مرنے کے لئے تیار ہو گیا.اس نے اپنے اوپر ایک بہت بڑی موت وارد کر لی.محض اس لئے کہ خدا کے وعدے اس متبرک مقام کی نسبت اس کی نسل کے ذریعہ سے پورے ہو جائیں.اب اگر وہ شخص پیدا نہیں ہوا جو اس مکہ کا مقصود ہے تو بتاؤ اسمٰعیل جھوٹا ہوا یا نہیں.جھوٹی قربانی ہی ایک ایسی چیز ہے جو کوئی نتیجہ پیدا نہیں کرتی.ورنہ سچی قربانی اپنا پھل ضرور پیدا کیا کرتی ہے.پس اگر اسمٰعیل نے سچی قربانی کی تھی اور تم بھی اس قربانی کی عظمت سے انکار نہیں کر سکتے تو تمہیں اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے کہ اس قربانی کے نتیجہ میں ضرور ایک کامل انسان پیدا ہونا چاہیے اسی طرح اگر تم ایک ایسے کامل انسان کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہو جو ابراہیمی دعا کے نتیجہ میں اسمٰعیلی نسل میں سے پیدا ہوا ہے تو اس کے معنے یہ ہیں کہ تمہارے نزدیک ابراہیمؑ کی قربانی بھی نعوذ باللہ غیر مقبول تھی اور اسمٰعیل کی قربانی بھی نعوذ باللہ مردود تھی.اگر اس کے اندر قربانی کرتے وقت تقویٰ ہوتا تو کس طرح ممکن تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کے تقویٰ کو ضائع کرتا اور اس کی قربانی کو ردّ کر دیتا.بہرحال دونوں میں سے ایک بات ضروری ہے.یا تم تسلیم کرو کہ ابراہیمؑ کی دعا نعوذ باللہ ضائع چلی گئی اور اسمٰعیلؑ کی قربانی دنیا میں کوئی نتیجہ پیدا نہ کر سکی اور یا پھر یہ تسلیم کرو کہ ابراہیمؑ اور اسمٰعیلؑ دونوں نے سچی قربانی کی تھی اور دونوں کی قربانی جس پھل کا تقاضا کرتی تھی وہ دنیا میں پیدا ہو گیا
Page 327
ہے کیونکہ اس طویل عرصہ کے بعد وہی اس مقام کا دعویدار ہے.پہلی بات کو تسلیم کرنے کی صورت میں تمہیں حضرت ابراہیمؑ اور حضرت اسمٰعیل دونوں کو جھوٹا قرار دینا پڑتا ہے.لیکن اگر دوسری بات مان لو تو پھر بے شک تم ان کے سچے ہونے کا دعویٰ کر سکتے ہو.مگر تمہاری تو یہ حالت ہے کہ تم ان کو سچا بھی کہتے ہوا ور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم کو بھی جھٹلاتے ہو جو اس دعا کا نتیجہ ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی اور اس قربانی کا پھل ہیں جو حضرت اسمٰعیل علیہ السلام نے کی.اگر تم ان کو جھوٹا کہتے ہو تو تمہیں ابراہیمؑ اور اسمٰعیلؑ کو بھی جھوٹا کہنا پڑے گا.اور اگر تم ابراہیمؑ اور اسمٰعیل کو سچا مانو تو پھر تمہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم کی صداقت پر بھی ایمان لانا پڑے گا.بہرحال یہ دونوں آپس میں لازم و ملزوم باتیں ہیں.اگر محمد صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم سچے ثابت ہوں تو ابراہیمؑ بھی سچے ثابت ہوتے ہیں.اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ثابت نہ ہوں تو ابراہیمؑ بھی سچے ثابت نہیں ہوتے اوراسمٰعیل بھی سچے ثابت نہیں ہوتے.جب اسمٰعیل نے اپنے آپ کو قربانی کے لئے پیش کیا تھا.اس وقت خدا نے کہا تھا کہ چونکہ اس نے میرے حکم پر اپنے آپ کو مرنے کے لئے پیش کر دیا ہے.اس لئے میں اسے وہ روحانی اولاد عطا کروں گا جو ساری دنیا کو زندہ کر دے گی اور میں اس ایک موت کے بدلے اس کے سارے خاندان کو حیاتِ ابدی بخشوں گا.اب اگر خاص نیت اور ارادہ سے حضرت اسمٰعیل علیہ السلام نے اپنے آپ کو پہلے ظاہر میں قربان ہونے کے لئے پیش نہیں کیا.ا ور پھر مکہ میں بسائے جانے کے وقت پیش نہیں کیا.تو ان کی نسل میں اس قسم کا بچہ پیدا نہیں ہو سکتا تھا.لیکن اگر انہوں نے سچی قربانی کی تھی تو ضرور تھا کہ ان کی نسل سے وہ سلسلہ چلتا جو دنیا کو زندگی بخشتا.پس بہرحال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم کی سچائی کے ساتھ ابراہیمؑ اور اسمٰعیلؑ کی سچائی وابستہ ہے اور یہی حقیقت اللہ تعالیٰ ان الفاظ میں کفار مکہ کے سامنے وَوَالِدٍ وَّمَا وَلَدَ کے الفاظ میں رکھتا ہے.کہ تم ابراہیمؑ کو بھی سچا مانتے ہو اور اسمٰعیلؑ کو بھی.مگر یہ کیسی عجیب بات ہے کہ تم اس شخص کو جھٹلا رہے ہو جس کی سچائی کے ساتھ ابراہیمؑ اور اسمٰعیلؑ کی سچائی وابستہ ہے.تم یہ تو مانتے ہو کہ ابراہیمؑ نے ایک رسول کے لئے دعا کی تھی.مگر جب اس دعا کے نتیجہ میں وہ رسول تم میں مبعوث ہو گیا ہے تو تم اس کو جھٹلا رہے ہو.تم یہ تو مانتے ہو کہ اسمٰعیلؑ نے جب قربانی کی تو خدا تعالیٰ نے اس کی اولاد کے بارہ میں ابراہیمؑ سے وعدے کئے اور کہا کہ اس کی نسل سے ایک ایسا انسان پیدا ہو گا جو دنیا کا مُزَکِّی ہو گا.مگر جب وہ روحانی فرزند ظاہر ہوگیا تو تم نے اس کا انکار کر دیا.اب بظاہر تم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم کا انکار کیا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ تم نے ابراہیمؑ کا بھی انکار کیا اور تم نے اسمٰعیلؑ کا بھی انکار کیا.کیونکہ یہ وہ شخص ہے جس کی صداقت پر یہ دونوں انبیاء
Page 328
گواہ ہیں.ابراہیمؑ گواہ ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اور اسمٰعیل گواہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم سچے ہیں اور تم نے جو طریق اس کی مخالفت میں اختیار کر رکھا ہے وہ اس مقصد کے بالکل خلاف ہے جس کو پورا کرنے کے لئے ابراہیمؑ نے دعائیں کیں اور جس کے ظہور کے لئے اسمٰعیلؑ نے قربانی کی.ممکن ہے اس موقعہ پر کسی شخص کے دل میں یہ سوال پیدا ہو کہ مکہ والے اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم کی مخالفت کرتے تھے تو اس لئے نہیں کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یا حضرت اسمٰعیل علیہ السلام کے مقصد کا پورا ہونا پسند نہیں کرتے تھے بلکہ ان کی مخالفت صرف اس لئے تھی کہ وہ اپنے متعلق یہ یقین رکھتے تھے کہ ہم نے اپنے وجود کے ذریعہ ابراہیمی دعا کو پورا کر دیا ہے یا ہم نے اپنے وجود کے ذریعہ اسمٰعیلی قربانی کو بے نتیجہ نہیں رہنے دیا.ہم لات، مناۃ اور عزّیٰ کی پرستش اس لئے کرتے ہیں کہ یہی ابراہیمؑ کا مقصد تھا اور یہی اسمٰعیلؑ کا مقصد تھا.یا ہم اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں تو اس لئے کہ ہم سمجھتے ہیں ابراہیمؑ نے اپنی دعا میں اللہ تعالیٰ سے جن باتوں کی خواہش ظاہر کی تھی وہ ساری کی ساری باتیں ہمارے ذریعہ سے پوری ہو چکی ہیں.اس لئے اب یہ ضرورت نہیں کہ کوئی اور شخـص آئے اور اپنے آپ کو ابراہیمی دعا کا نتیجہ یا اسمٰعیلی قربانی کا مقصود قرار دے.ابراہیمؑ نے جو دعائیں کیں.وہ ہمارے ذریعہ سے پوری ہو چکی ہیں اور اسمٰعیلؑ نے جس مقصد کے لئے قربانی کی تھی وہ بھی ہمارے وجود کے ذریعہ حاصل ہو چکا ہے.ہم اس مقصد کی طرف جا رہے ہیں جو ابراہیمؑ اور اسمٰعیلؑ کا مقصد تھا.اور انہی عقائد کو ہم نے اختیار کیا ہوا ہے جو ان کے عقائد تھے.اس لئے گو یہ عقائد برے نظر آئیں.تمہیں لات اور مناۃ اور عزّیٰ کی پرستش بری دکھائی دے.مگر ہمارے نزدیک جب ابراہیم اور اسمٰعیل دونوں کی یہی تعلیم تھی.یہی مقصد بعثت تھا.تو ہم پر اس بات کا کیا اثر ہو سکتا ہے کہ ہم نے ابراہیمی دعا کو عبث قرار دے دیا ہے یا اسمٰعیلی قربانی کے مقصد کو نظر انداز کر دیا ہے.اس اعتراض کے متعلق یاد رکھنا چاہیے کہ اس کے دو۲ جواب ہیں پہلا جواب تو یہ ہے کہ یہ ایک عجیب بات ہے کہ مکہ کے لوگ لات اور مناۃ اور عزّیٰ وغیر کی پرستش کرتے تھے.مگر ان میں سے کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا جو یہ کہتا ہو کہ ابراہیمؑ بتوں کی پرستش کرتا تھا یا اسمٰعیلؑ بتوں کی پرستش کرتا تھا.یہ خدا نے ایک عجیب ثبوت رکھا ہوا تھا کہ ان کو کبھی جرأت ہی نہیں ہوئی تھی کہ وہ ابراہیمؑ اور اسمٰعیلؑ کو بھی شرک میں ملوث کریں اور چونکہ وہ خود اپنے عقائد کے رو سے یہ باتیں ان کی طرف منسوب نہیں کرتے تھے.اس لئے وہ مسلمانوں کے سامنے اس بات کو پیش ہی نہیں کر سکتے تھے کہ ہم جس تعلیم پر قائم ہیں وہ ابراہیمی اور اسمٰعیلی مقصد کو پورا کرنے والی ہے.کیونکہ وہ خود ان کو
Page 329
شرک میں ملوث نہیں سمجھتے تھے.دوسرا جواب یہ ہے کہ بے شک مذہب ایک ایسی چیز ہے جو زیر بحث ہوتی ہے اورا س میں بہت کچھ اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں.لیکن اور مذہبی اختلافات کو نظر کرتے ہوئے اس حقیقت سے بھی کبھی اغماض نہیں کیا جا سکتا کہ وہ لوگ اس بات کے قائل تھے کہ خانہ کعبہ کی بنیاد کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا کی تھی اور وہ دعا بہرحال پوری ہونی چاہیے.مگر جو کچھ اس وقت مکہ کی حالت تھی اس کے لحاظ سے وہ قطعی طور پر ایک منٹ کے لئے بھی یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ مکہ کا وجود ابراہیمی دعا کا مصداق ہے.کیونکہ دعا یہ تھی کہ خدا مکہ کو ساری دنیا کا مرجع بنا دے.وہ مذہبی لحاظ سے تو کہہ سکتے تھے کہ ہم سچے ہیں.وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ہم اگر شرک کرتے ہیں اگر لات اور مناۃ اور عزّیٰ کی پرستش کرتے ہیں تو اچھا کرتے ہیں.مگر کیا مکہ والے یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ عرب ساری دنیا کا مرکز ہے اور ابراہیمؑ کی دعا پوری ہو چکی ہے.ان کو نظر آ رہا تھا کہ یہ خانہ ابھی خالی ہے اور مکہ کو ابھی تک وہ اعزازحاصل نہیں ہوا جس کے لئے ابراہیمؑ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت دعا کی تھی.وہ دنیاوی طور پر معمولی حیثیت کے لوگ جن کو عرب میں بھی کوئی خاص عزت حاصل نہیں تھی کجا یہ کہ بیرونی دنیا کی نگاہ میں ان کو کوئی خاص اعزاز حاصل ہوتا ان کا اپنے آپ کو ابراہیم اور اسمٰعیل کی دعا کا مصداق قرار دینا تو بڑی بات ہے وہ تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے تھے کہ عرب پر ہی انہیں کوئی دبدبہ اور حکومت حاصل ہے.پس انہیں یہ تسلیم کرنا پڑتا تھا کہ روحانی لحاظ سے ابھی مکہ کی عظمت اور اس کی شان وشوکت میں اضافہ ہونے والا ہے ابھی ایک خلا باقی ہے جس نے پُر ہونا ہے.ابھی اس نے دنیا جہان کا مرکز بننا ہے.ابھی اسے یہ اعزاز حاصل ہونا ہے کہ دنیا کے چاروں طرف سے لوگ یہاں آئیں.یہ عظمت مکہ کو پہلے کہاں حاصل تھی.بے شک عرب لوگ حج کے لئے مکہ میں آتے تھے.مگر دنیا کے چاروں اطراف سے ہر ملک اور ہر علاقہ کے لوگ مکہ میں نہیں آتے تھے.وہ ایک ملک کا مرکز تو کہلا سکتا تھا مگر ساری دنیا کا مرکز نہیں تھا.حالانکہ ابراہیمی دعا یہ تھی کہ خدا اسے دنیا کا مرکز بنا دے.خدا اس میں تمام عالم کے اطراف سے لوگوں کو کھینچ کھینچ کر لائے اب کجا مکہ کی وہ حالت اور کجا ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ ابھی مکہ اپنے اصل اعزاز سے بہت پیچھے تھا.ابراہیمؑ کی دعا ابھی پوری ہونے والی تھی اسمٰعیلؑ کی قربانی ابھی اپنا پھل دینے والی تھی اور مکہ کو ابھی وہ طاقت حاصل ہونے والی تھی جب اسے ساری دنیا کا مرکز قرار دیا جانے والا تھا.پس مکہ والے یہ کہہ ہی نہیں سکتے تھے کہ ابراہیمؑ کی دعا پوری ہو چکی ہے.وہ جانتے تھے کہ بےشک حج کے لئے عرب لوگ مکہ میں آ جاتے ہیں مگر بیرونی دنیا کی نگاہ میں انہیں کوئی اعزاز حاصل نہیں چنانچہ
Page 330
اس کے متعلق خود تاریخی شہادات بھی موجود ہیں.جس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ عرب والوں کو کیسی تحقیر کی نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا.جب رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم نے قیصر کو تبلیغی خط لکھا اور وہ اسے پہنچا تو وہ اس خط کو پڑھ کر خاص طور پر متاثر ہوا اور اس نے درباریوں سے کہا کہ اس خط کا لکھنے والا بڑا دلیر انسان معلوم ہوتا ہے.لوگوں سے پتہ لگانا چاہیے کہ یہ کون ہے کیا دعویٰ کرتا ہے اور اس کے ساتھ کیا کیا واقعات گذرے ہیں.اگر مکہ کے کوئی آدمی یہاں آئے ہوئے ہوں تو ان کو میرے دربار میں پیش کیا جائے تاکہ میں ان سے اس خط کے لکھنے والے کے حالات دریافت کروں.اتفاق کی بات ہے اللہ تعالیٰ نے چونکہ مکہ والوں پر حجت تمام کرنی تھی.ابوسفیان ایک تجارتی قافلہ کے ساتھ وہاں موجود تھا.لوگوں نے اسے بادشاہ کے دربار میں پیش کر دیا.ابوسفیان وہ شخص تھا جو مکہ کا کمانڈر تھا.اہل مکہ کا سردار تھا.وہ قیصر کے دربار میں پیش کیا گیا.مگر اس طور پر نہیں کہ مقابل کی حکومت کا کوئی بادشاہ آیا ہو.اس طور پر بھی نہیں کہ کسی چھوٹی حکومت کا کوئی سردار آیا ہو.اس طور پر بھی نہیں کہ مقابل کی کسی حکومت کا کوئی جرنیل آیا ہو.بلکہ اس طور پر اسے قیصر کے سامنے پیش کیا گیا جس طرح ایک مجرم کو کسی بادشاہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے.ابوسفیان پیش ہوا تو بادشاہ نے بعض دوسرے لوگوں سے جو اس کے ساتھ تھے کہا کہ میں اس سے بعض سوالات کروں گا.اگر یہ ان سوالات کا سچ سچ جوا ب دے تو تم چپ رہنا لیکن اگر کسی بات کا جواب دیتے ہوئے جھوٹ بولے تو فوراً مجھے بتانا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے (صحیح بـخاری کتاب بدء الوحی باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ وسلم ).یہ کیسی ذلت ہے جو قیصر کے دربار میں پہنچتے ہی ابوسفیان کو پہنچی یہ وہ شخص ہے جو اپنے آپ کو مکہ کا بادشاہ سمجھتا تھا.یہ وہ شخص ہے جسے قوم نے منتخب کر کے اپنا لیڈر بنایا ہوا تھا.یہ وہ شخص ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم کے مقابلہ میں اپنی قوم کے لیڈر کے طور پر پیش ہوتا تھا.یہ وہ شخص ہے جس کو مکہ سے تعلق رکھنے والے عربوں نے اکٹھے ہو کر اپنا رئیس منتخب کیا ہوا تھا.یہ قیصر کے دربار میں پیش ہوتا ہے تو وہ یہ تسلیم نہیں کرتا کہ یہ کسی بالمقابل حکومت کا بادشاہ ہے.قیصر یہ بھی تسلیم نہیں کرتا کہ یہ کسی ریاست کا مالک ہے.قیصر یہ بھی تسلیم نہیں کرتا کہ یہ کسی فوج کا کمانڈر ہے کیونکہ وہ یہ ماننے کے لئے تیار نہیں تھا کہ عرب کوئی بالمقابل حکومت ہے.وہ یہ ماننے کے لئے تیار نہیں تھا کہ عرب کوئی ریاست ہے.وہ یہ ماننے کے لئے تیار نہیں تھا کہ عرب کوئی منظم قوم ہے جس کا کمانڈر ابوسفیان ہے وہ اسے تخت پر نہیں بٹھاتا.وہ اسے کرسی پر نہیں بٹھاتا.اسے کسی چیز پر بھی بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتا.بلکہ اسے اپنے سامنے کھڑا ہونے کا حکم دیتا ہے.اور وہ اسے صرف ایک معمولی تاجر کی حیثیت
Page 331
دیتا ہے.یہ تو قیصر کا ابوسفیان اور اس شہر کے متعلق فیصلہ ہے جس کا وہ نمائندہ تھا.مگر ابوسفیان کا اپنا فیصلہ اس سے بھی عجیب تر ہے جب ابو سفیان سے یہ مجرموں والا سلوک ہوا تو اس نے ایک لفظ بھی بطور احتجاج کے نہیںکہا.اگر وہ مکہ کو ایک حکومت قرار دیتا اور اپنے آپ کو واقعی ایک حکومت کا سردار کہتا تو وہ احتجاج کرتا اور کہتا میں ایک حکومت کا رئیس ہوں مجھے اپنے برابر جگہ دو.مگر وہ خاموشی سے اس ذلت کو برداشت کر لیتا ہے.علاوہ ازیں ہم دیکھتے ہیں کہ جب قیصر کے دربار میں رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم کا خط پیش ہوا اور اس نے لوگوں کو بتایا کہ مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم نے لکھا ہے کہ میں اس پر ایمان لے آؤں.بتاؤ اس بارہ میں تمہاری کیا رائے ہے.تو ابوسفیان محض اس خط کے لکھنے سے ہی مرعوب ہو گیا اور اس نے ساتھیوں سے کہا لَقَدْ اَمِرَ اَمْرُ ابْنِ اَبِیْ کَبْشَۃَ (صحیح بـخاری کتاب بدء الوحی باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم) کہ محمد (رسول اللہ) تو بہت بڑا ہو گیا ہے اس نے قیصر کو خط لکھ دیا ہے.اور وہ اس خط کی طرف توجہ دے رہا ہے.یہ اس کی حیثیت ہے کہ وہ ایک قوم کا بادشاہ ہے اور پھر اس بات پر حیران ہوتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر کو خط لکھ دیا.اگر حقیقی بادشاہ ہوتا تو اس کے لئے اس میں تعجب کی کون سی بات تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم نے قیصر کو خط لکھ دیا ہے.اگر کہو کہ اس نے خط لکھنے کی وجہ سے نہیں بلکہ اس وجہ سے یہ الفاظ کہے تھے کہ قیصر رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم کے خط سے متاثر ہوا تھا.تو بہرحال اس سے بھی پتہ لگ سکتا ہے کہ مکہ والے اپنی کیا شان سمجھتے تھے.اگر تو وہ خط لکھنے سے متاثر ہوا ہے تو یہ بہت ہی گھٹیا بات ہے.اور اگر وہ اس بات سے متاثر ہوا ہے کہ ہم تو بالکل معمولی تھے.ہماری دنیا کی نگاہ میں کوئی عزت نہیں تھی.اب محمد صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم ایک ایسا شخص پیدا ہو گیا ہے جس کی وجہ سے قیصر بھی مرعوب ہونے لگ گیا ہے.تو یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ مکہ والے تسلیم کرتے تھے کہ ابھی ابراہیمی دعا پوری نہیں ہوئی.اگر ابراہیم کی دعا پوری ہو چکی ہوتی اور اگر عرب ما نتے کہ مکہ ساری دنیا کی نگاہ میں ایک غیر معمولی عظمت رکھتا ہے تو کیا ابراہیمؑ اور اسمٰعیلؑ کی دعا پوری ہو جانے کا وہ یہی ثبوت پیش کرتے کہ ہمارا بادشاہ ابوسفیان قیصر کے دربار میں پیش ہوا اور اس سے یہ سلوک ہوا.یا کیا عتبہ اور شیبہ اور دوسرے بڑے بڑے عمائد اپنی عزت اور اقتدار کا کوئی ثبوت پیش کر سکتے تھے.اہل عرب کو دنیا کی نگاہ میں جو عزت حاصل تھی اس کا اندازہ تو اسی سے ہو جاتا ہے کہ ایران کے بادشاہ نے مسلمانوں کے حملہ کے وقت اسلامی لشکر کو یہ پیشکش کی تھی کہ ایک ایک اشرفی لے لو اور واپس چلے جاؤ.وہ سمجھتا تھا کہ عرب کے لوگ ایسے ذلیل ہیں کہ ایک ایک اشرفی دے کر ان کو خریدا جا سکتا ہے.یہ ایران کے
Page 332
بادشاہ کے عربوں کے متعلق مکہ والوں کے اخلاق کودیکھ کر اندازہ تھا اور قیصر کا جو سلوک تھا وہ ابو سفیان والے واقعہ سے ظاہر ہے.وہ قیصر کے دربار میں پیش ہوا تو اس نے ایک تاجر سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہ سمجھی جسے ضرورت کے موقعہ پر جھوٹ بولنے سے بھی عار نہیں ہوتا.بلکہ ابوسفیان کی حیثیت تو اتنی بھی ثابت نہیں ہوئی جتنی مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی کی.اس نے تو مسٹر ڈگلس سے عدالت میں کہا تھا کہ مجھے کرسی ملنی چاہیے.مگر ابوسفیان کے منہ سے اتنا بھی نہ نکلا کہ مجھے کرسی دو.کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر میں نے کرسی کا مطالبہ کیا تو مجھے جوتیاں مار کر نکال دیا جائے گا.اب بتاؤ کیا وہ ان واقعات کو پیش کر کے کہہ سکتے تھے کہ ابراہیمؑ اور اسمٰعیلؑ کی دعا کا یہ ظہور ہے.وہ جانتے تھے کہ یہ دعا ابھی پوری ہونے والی ہے.اور مکہ کو ابھی وہ اعزاز حاصل نہیںہوا جس کا ابراہیمی دعا میں ذکر آتا ہے.پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ابراہیمؑ اور اسمٰعیلؑ کو شہادت کے طور پر پیش کرتے ہیں.ان کی ایک دعا تھی جس کو تم بھی تسلیم کرتے ہو.تم بتاؤ کہ آخر وہ دعا گئی کہاں.اس دعا کے مطابق جو اس وقت مدعی کھڑا ہوا ہے تم اس کے متعلق کہتے ہو کہ وہ جھوٹا ہے اگر یہ بھی جھوٹا ہے تو پھر اس دعا کو پورا کون کرے گا اور وہ کون ہوگا جو وَالِد اور وَلَد کی دعاؤں کا مصداق ہو گا.تم اس کے سوا اور کوئی وجود ایسا پیش نہیں کر سکتے جو ان دعاؤں کے نتیجہ میں ظاہر ہونے کا اعلان کر رہا ہو.پس ابراہیمؑ اور اسمٰعیل کی دعائیں بڑا بھاری ثبوت ہیں اس بات کاکہ محمدرسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم خدا تعالیٰ کے سچے اور راستباز رسول ہیں.دوسرے معنے اس کے یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ ہم گذشتہ زمانہ کے ایک واقعہ کو بطور شہادت کے پیش کرتے ہیں.اور وہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے کا واقعہ ہے.تم اس واقعہ پر غور کرو اور دیکھو کہ اس کو کس طرح ایک بے آب و گیاہ جنگل میں خدا تعالیٰ کے حکم کے ماتحت پھینک دیا گیا تھا.لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے بچایا اور پروان چڑھایا اور ایک بڑی نسل کا باپ بنایا.اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر آپ کے رشتہ دار مکہ سے نکال دیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی اسی طرح مدد کرے گا جس طرح اسمٰعیل علیہ السلام کی اس نے مدد کی تھی.وہ لوگ جو بائیبل کا مطالعہ رکھتے ہیں جانتے ہیں کہ بائیبل اس نظریہ کو پیش کرتی ہے کہ حضرت ہاجرہ جو حضرت اسمٰعیل علیہ السلام کی والدہ تھیں ان سے سارہ کی لڑائی ہوئی اور اس نے ناراض ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ہاجرہ اور اس کے بیٹے اسمٰعیل کو اپنے گھر سے نکال دو.حضرت ابراہیم علیہ السلام نے الٰہی اشارات اس کی تائید میں پائے.چنانچہ ماں اور بیٹے دونوں کو گھر سے نکال کر مکہ کی وادی میں لا کر چھوڑ گئے.وہ جگہ جہاں ان کو رکھا گیا وہاں کھانے کا کوئی سامان نہ تھا.پینے کا کوئی سامان نہ تھا.رہائش کے لئے کوئی جگہ نہ تھی.وہاں
Page 333
ایک دوسرے سے ملنے کے لئے کوئی آبادی نہیں تھی.ایک سنسان اور ویران جنگل میں جہاں نہ پانی کا ایک قطرہ تھا اور نہ غذا کا ایک دانہ.کھلے آسمان کے نیچے خدا پرتوکل کرتے ہوئے وہ دو کمزور اور نحیف و ناتوان جانوں کو چھوڑ گئے اوراس لئے چھوڑ گئے کہ خدا نے ان سے کہا تھا کہ وہ ایسا کریں.جب انہوں نے خدا کے لئے یہ قربانی کی تو خدا نے بھی آسمان پر ان کی اس قربانی کو قبول فرمایا اور اس نے رفتہ رفتہ وہاں ایک شہر آباد کر دیا.پھر خدا نے اس مقام کو یہ عظمت دی کہ وہ لوگوں کا مرجع بن گیا.بیت اللہ کی اس میں تعمیر ہوئی اور اسے ابراہیم علیہ السلام کے ذریعہ یہ شرف بخشا گیا کہ اسے امن و امان کا مرکز قرار دیا گیا.اس واقعہ کو پیش کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک دن تم بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شہر میں سے اسی طرح نکال دو گے جس طرح سارہ نے ہاجرہ اور اسمٰعیل کو نکالا تھا.مگر ہم کو بھی قسم ہے ابراہیمؑ اور اس کے بیٹے اسمٰعیلؑ کی کہ جس طرح وہاں ایک ویران اور سنسان جنگل کو ہم نے ایک عظیم الشان شہر کی شکل میں تبدیل کر دیا تھا اور پھر ہم نے اسے یہاں تک عظمت دی کہ اسے بلد الحرام قرار دے دیا.اسی طرح جس گاؤں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم ہجرت کر کے جائیں گے اس گاؤں کو بھی ہم شہر بنا دیں گے اور پھر اس شہر کو بھی یہ عظمت دیں گے کہ اسے مکہ کی طرح بلد الحرام قرار دیں گے پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے اس باپ کی قسم ہے جس نے اپنی بیوی کے کہنے پر اپنے بیٹے کو نکالا.وہ بیٹا ایسی حالت میں نکلا جبکہ وہ بےکس بے زر اور بے پَر تھا.کوئی اس کا یار اور مددگار نہیں تھا.مگر خدا نے اسے رفتہ رفتہ بہت بڑی طاقت کا مالک بنا دیا.تم بے شک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شہر میں سے نکال دو.مگر یاد رکھو پھر مکہ منفرد عزت رکھنے والا شہر نہیں رہے گا.بلکہ اسی قسم کی عزت والا ایک اور شہر اس کے مقابل میں کھڑا کر دیا جائے گا.چنانچہ دیکھ لو رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم کو مکہ میں سے نکالا گیا.مگر آخر آپ کو وہ عظمت حاصل ہوئی کہ آپ نے ایک دن سب لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا اے لوگو جس طرح ابراہیمؑ کے ذریعہ مکہ مکرمہ کو ایک خاص اعزاز بخشا گیا تھا میرے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدینہ کو بھی وہی اعزاز عطا کیا گیا ہے.جس طرح مکہ میں جان کی عزت کی جاتی ہے اسی طرح مدینہ میں جان کی عزت کی جائے.جس طرح وہاں درخت کاٹنے جائز نہیں اسی طرح مدینہ میں بھی درختوں کا کاٹنا جائز نہیں.جس طرح وہاں فتنہ وفساد اور قتل و خونریزی کی سخت ممانعت ہے اسی طرح مدینہ میں بھی فتنہ وفساد اور قتل و خونریزی کی سخت ممانعت ہے.غرض وہ تمام باتیں جو مکہ کے متعلق تھیں.رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم نے مدینہ منورہ پر بھی عائد کر دیں.آخر یہ بھی غور کرنے والی بات ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم کو مدینہ کو حرم بنانے کا اختیار کس نے دیا تھا.
Page 334
بعض لوگ اعتراض کرتے ہوئے کہہ دیا کرتے ہیں کہ ایسا حکم دینا خدا کا کام تھا.محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم کا یہ اختیار نہیں تھا کہ خود بخود ایسا حکم دے دیتے.ان نادانوں کو یہ معلوم نہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم کو قرآن کریم کا وہ گہرا علم بخشا گیا تھا جو دنیا میں اور کسی شخص کو عطا نہیں کیا گیا.آپ نے مدینہ منورہ کے متعلق جو حکم دیا وہ اسی آیت سے ماخوذ تھا کہ لَاۤ اُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ.وَ اَنْتَ حِلٌّۢ بِهٰذَا الْبَلَدِ.وَ وَالِدٍ وَّ مَا وَلَدَ میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کو بسانے والے کی اور میں قسم کھاتا ہوں اس بیٹے کی جو اس شہر میں آکر بسا تھا.بے شک تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم کو اس شہر میں سے نکال دو.مگر یاد رکھو جس شہر میں وہ جائے گا.اس شہر کو مکہ کا قائم مقام بنا دیا جائے گا اور اسے وہی عزتیں دے دی جائیں گی جو اس شہر کو حاصل ہیں.مکہ اپنے اس اعزاز میں منفرد نہیںرہے گا.تیسرے معنے اس کے یہ بھی ہیں کہ وَوَالِدٍ وَّمَا وَلَدَ سے مراد رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم اور آپ کی امت ہے.اور یہ فرمایا گیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم اور آپ کی جماعت اس بات پر شاہد ہے کہ خدا تعالیٰ اسلام کو ترقی دینے والا ہے.جس طرح اس بلد الحرام سے رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم کا نکلنا اور پھر بڑی شان و شوکت کے ساتھ اس میں واپس آنا اس بات کا ثبوت ہو گا کہ جو باتیں اس کی طرف سے پیش کی جارہی ہیں بالکل درست ہیں.اسی طرح خود رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم اور آپ کی امت اپنی ذات میں اس بات کا ثبوت ہو گی.کہ ان لوگوں کو کوئی قوم مٹا نہیں سکتی.دنیا میں دو قسم کی شہادت ہوتی ہے.ایک اندرونی اور ایک بیرونی.بیرونی شہادت پھر دو قسم کی ہوتی ہے.ایک مادی اور ایک روحانی.مادی شہادت تو یہ ہے کہ ایک شخص کے ساتھ کئی ہزار کا لشکر ہو.لڑائی کا سازوسامان ان کے پاس موجود ہو.اطاعت کا مادہ سب میں بدرجہ اتم پایا جاتا ہو.ایسے انسان کو دیکھ کر ہر شخص اندازہ لگا سکتا ہے کہ یہ ضرور جیت جائے گا کیونکہ کامیابی کے لئے جس قدر سامانوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ سب اس کے پاس موجود ہیں.روحانی شہادت یہ ہوتی ہے کہ ایک شخص خدا تعالیٰ کی طرف سے کھڑا ہوتا ہے اور وہ اپنی کامیابی کے متعلق اللہ تعالیٰ سے علم پا کر پیشگوئیاں کرتا ہے.جو لوگ مومن ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ شخص بہرحال جیت جائے گا.کیونکہ خدائی وعدے اس کے ساتھ ہیں.لیکن ایک شہادت اندرونی ہوتی ہے.جسے انگریزی میں انْ ٹَرِن زِکْ ویلیو INTRINSIC VALUE کہا جاتا ہے.یہ ایسی ہی بات ہے جیسے کہتے ہیں ’’ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات ‘‘وہ بظاہر کمزور اور بے حقیقت نظر آتے ہیں.لیکن ان کے اندر ایسے اوصاف اور ایسی قابلیتیں پائی جاتی ہیں.اور ان کی اخلاقی طاقت ایسی زبردست
Page 335
ہوتی ہے کہ باوجود ان کے کمزور ہونے کے لوگ یہ اعتراف کرنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ ان لوگوں کے مقابل پر کوئی قوم ٹھہر نہیں سکتی.اس جگہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرف تو اسلام کی ترقی کے متعلق پیشگوئیاں بیان کیں اور فرمایا کہ تم خواہ کچھ کہو.لیکن ہم یوں کہتے ہیں.یا ابراہیمؑ نے یہ پیشگوئی کی تھی جو بہرحال پوری ہو گی.اور دوسری طرف فرمایا ہم نہ صرف ان پیشگوئیوں کو پیش کرتے ہیں جو لیالی عشـر میں اور ان لیالی کے گذرنے کے بعد پوری ہو کر اس بات کا ثبوت ہوں گی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ سچا ہے.بلکہ ہم اس کی صداقت اور راستبازی کا اور اس کے دنیا پر ایک دن غالب آ جانے کا تمہارے سامنے ایک اندرونی ثبوت بھی پیش کرتے ہیں کہ تم محمد صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم اور ان کے اتباع کو دیکھ لو ان کے اندر جو اوصاف پائے جاتے ہیں کیا یہ ہارنے والے لوگوں کے اندر پائے جاتے ہیں.یا غالب آنے والے لوگوں کے اندر موجود ہوتے ہیں.گویا وَالِدا ور مَاوَلَد میں اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم اور آپ کی جماعت کے کیرکٹر کو پیش کیا ہے اور فرمایا ہے تم ان لوگوں کے کیرکٹر سے اپنا کیرکٹر ملا کر دیکھو.تمہارا کیرکٹر تو وہ ہے جو ان الفاظ میں بتایا گیا ہے کہ كَلَّا بَلْ لَّا تُكْرِمُوْنَ الْيَتِيْمَ.وَلَا تَحٰٓضُّوْنَ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ.وَ تَاْكُلُوْنَ التُّرَاثَ اَكْلًا لَّمًّا.وَّ تُحِبُّوْنَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا (الفجر:۱۸تا۲۱) اور یہ بات واضح ہے کہ اس کیرکٹر والے کبھی جیت نہیں سکتے.اب بتاتا ہے کہ اس وَالِد اور مَاوَلَد کے اندر جو کیرکٹر پائے جاتے ہیں.اس کیرکٹر کے مالک کبھی ہار نہیں سکتے.تمہارا کیرکٹر تو یہ تھا کہ یتیم کو پوچھنا نہیں.مسکین کو کھانا نہیں کھلانا.جائیدادیں آئیں تو ان کو لٹا دینا یا مال سے اتنی محبت رکھنا کہ ضرورت پر بھی اس کو خرچ نہ کرنا اور انتہائی بخل سے کام لینا.یعنی ایک طرف تو تمہارے بعض حصۂ قوم میں اتنا اسراف پایا جاتا ہے کہ باپ دادا کی جائیدادیں آتی ہیں تو وہ ان کو تباہ کر دیتے ہیں اور دوسری طرف تم میں سے کچھ لوگوں کے اندر ایسا بخل پایا جاتا ہے کہ مال آئے تو اسے بند کر کے رکھ لیتے ہیں.گویا کچھ تو ایسے ہیں جو اپنے مال کو بے مصر ف خرچ کرتے ہیں.اور کچھ وہ افراد ہیں جو بامقصد بھی صرف نہیں کرتے یہ چار قسم کی صفات جس قوم میں ہوں تم خود ہی غور کرو کہ آیا وہ قوم کبھی جیت سکتی ہے.اس کے مقابل میں تم اس باپ اور اس کے بیٹوں کو دیکھو.یہاں گو نام بنام ایک ایک صفت کا ذکر نہیں کیا گیا.مگر تقابل سے صاف ظاہر ہے کہ جن برائیوں کا ذکر دشمنوں کے بارہ میں کیا گیا ہے.انہی کے مقابل کی نیکیاں ان لوگوں میں پائے جانے کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے.چونکہ کفار کی برائیاں یہ بیان کی تھیں کہ وہ یتامیٰ کی طرف توجہ نہیں کرتے.مساکین کو کھانا نہیں کھلاتے.اسراف میں مبتلا رہتے ہیں.یا اتنے بخل سے کام لیتے ہیں کہ ضرورت حقہ پر بھی روپیہ خرچ کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتے.اس جگہ انہی چار عیبوں کے
Page 336
مقابل کی خوبیوں کے متعلق دعویٰ کیا گیا ہے.کہ وہ اس باپ اور اس کی اولاد میں پائی جاتی ہیں.ان میں اکرام یتیم بھی پایا جاتا ہے.ان میں مساکین کی پرورش کا جذبہ بھی موجود ہے.وہ اسراف بھی نہیں کرتے.اور ضرورت پر اپنے مالوں کو خدا تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرانے سے دریغ بھی نہیں کرتے.چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ گھبرائے کہ یہ کہیں میرا امتحان نہ ہو.تو اسی حالت میں آپ حضرت خدیجہؓ کے پاس آئے اور ان سے اس واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ لَقَدْ خَشِیْتُ عَلٰی نَفْسِیْ مجھے تو اپنے نفس کے متعلق ڈر پیدا ہو گیا ہے.حضرت خدیجہ نے یہ سنتے ہی بلاتکلف بغیر سوچنے اور بغیر کسی فکر و تردّد سے کام لینے کے نہایت اطمینان کے ساتھ کہا کَلَّا وَاللہِ مَا یُـخْزِیْکَ اللہُ اَبَداً اِنَّکَ لَتَصِلُ الرَّحِـمَ وَتَـحْمِلُ الْکَلَّ وَتَکْسِبُ الْمَعْدُوْمَ وَتَقْرِی الضَّیْفَ وَتُعِیْنُ عَلٰی نَوَائِبِ الْـحَقِّ (الـصحـیـح الـبـخـاری باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم ) خدا کی قسم.خدا آپ کو کبھی ذلیل نہیں کر سکتا.کیونکہ آپ وہ ہیں جو صلہ رحمی کرتے ہیں.آپ وہ ہیں جو سچائی سے کام لیتے ہیں.آپ وہ ہیں جو لوگوں کے بوجھ بٹاتے ہیں.آپ وہ ہیں جنہوں نے تمام معدوم اخلاق کو اپنے اندر پیدا کیا ہوا ہے.آپ وہ ہیں جو مہمان نوازی کرتے ہیں.اور آپ وہ ہیں جو حق کی راہ میں لوگوں کے مددگار بنتے ہیں.آپ جیسے انسان کو اللہ تعالیٰ کس طرح ضائع کر سکتا ہے.اب دیکھ لو حضرت خدیجہ نے جو باتیں بیان فرمائی ہیں ان سب میں وہ اخلاق آ گئے جو کفار کے اندر موجود نہیں تھے.انہوں نے فرمایا کہ تَقْرِی الضَّیْفَ آپ مہمان نوازی کرتے ہیں.اس میں یہ بات آ گئی.آپ کے اندر مال کی ایسی محبت نہیں تھی کہ آپ اسے بند کر کے بیٹھ رہتے.بلکہ ہر جائز ضرورت پر آپ اسے خرچ کر دیتے تھے.پھر انہوں نے ایک خوبی ان الفاظ میں بیان فرمائی کہ تَـحْمِلُ الْکَلَّ.آپ لوگوں کے بوجھ بٹاتے ہیں.اس میں یتامیٰ اور مساکین بھی شامل ہیں.کیونکہ جو شخص کسی کام کے قابل نہ ہو وہ دوسروں کے لئے ایک بوجھ ہوتا ہے.یتیم کسی کام کے قابل نہیں ہوتا بوجہ اپنی کم سنی کے اور مسکین بھی کسی کام کے قابل نہیں ہوتا بوجہ فقدان روپیہ کے بے شک اس میں اور باتیں بھی شامل ہیں.مگر اکرام یتیم اور مساکین پروری دونوں بہرحال تَـحْمِلُ الْکَلَّمیں شامل ہیں.پھر جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم لوگوں کی ضروریات کے لئے روپیہ خرچ کیا کرتے تھے تو یہ لازمی بات ہے کہ جو شخص روپیہ خرچ کرنے والا ہو وہ کنجوس نہیں ہو سکتا پس بخل کی بھی نفی آ گئی.پھر اسراف بھی جاتا رہا.کیونکہ حضرت خدیجہؓ فرماتی ہیں تَکْسِبُ الْمَعْدُوْمَ وہ اخلاق جو قوم میں سے مٹ چکے ہیں.ان کو دوبارہ اپنی قوم میں واپس لا رہے ہیں.گویا وہ سب اخلاق جن کو آپ کی قوم کھو چکی تھی.وہ آپ کے ذریعہ دوبارہ حاصل ہو رہے ہیں.
Page 337
اس سے یہ نتیجہ خودبخود نکل آیا کہ محمد صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم مسرف نہیں تھے.پس حضرت خدیجہؓ کی گواہی اپنی ذات میں اس بات کا ایک قطعی اور یقینی ثبوت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم کے اندر وہ سب اوصاف و کمالات پائے جاتے تھے جو ایک ترقی کرنے والے وجود کے اندر پائے جانے ضروری ہیں.وَالِد کے بعد وَلَد کا ذکر آتا ہے ان کے اخلاق اور ان کی قربانیوں کو بھی جب دیکھا جاتا ہے تو حیرت آتی ہے.رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم پر ایمان لانے کے بعد انہوں نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ وطن کی قربانی، یتامٰی کی خبر گیری، مساکین کی پرورش، دینی ضروریات کے لئے روپیہ صرف کرنا یہ سب خوبیاں ان کے اندر اپنی پوری شان کے ساتھ موجود تھیں.چنانچہ ان کے اخلاق اور ان کی قربانیوں کا یہ ایک زندہ ثبوت موجود ہے کہ انہوں نے خدا تعالیٰ کے لئے اپنے وطنوں کو قربان کر دیا.اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کر لیا اور ہر قسم کی موت کو اپنے اوپر خوشی سے وارد کر لیا.غرض اس مقام پر اللہ تعالیٰ وَالِد اور مَا وَلَد دونوں پیش کرتا ہے.اور بتاتا ہے کہ ان اوصاف کی موجودگی میں تم یہ کس طرح کہہ سکتے ہو کہ یہ لوگ نہیں جیتیں گے پیشگوئیوں کے متعلق تو تم یہ کہہ سکتے ہو کہ جب وہ پوری ہوں گی تو دیکھا جائے گا.مگر یہ چیز تو تمہارے سامنے موجود ہے.تم ہر وقت دیکھ سکتے ہو کہ تم میں کیسے اخلاق پائے جاتے ہیں.اور مسلمانوں میں کس قسم کے اخلاق پائے جاتے ہیں.تمہارے اخلاق اس بات کا ثبوت ہیں کہ تم لوگ ہارنے والے ہو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم اور ان کی جماعت کے اخلاق اس بات کا ثبوت ہیں کہ وہ لوگ جیتنے والے ہیں.بطور تنزل اس آیت کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ وَوَالِدٍ وَّ مَاوَلَدَ سے آدم اور اس کی تمام اولاد مراد لی جائے.اور آیت کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ ہم محمدر سول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم کی صداقت کے ثبوت میں تمام بنی نوع انسان کو بطور شہادت پیش کرتے ہیں.تم دیکھ لو کہ نوعِ انسانی میں سے کچھ لوگ عزت پانے والے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ذلت پانے والے ہوتے ہیں.عزت پانے والوں میں جو خوبیاں موجود ہوتی ہیں وہ سب کی سب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم اور ان کے ساتھیوں میں پائی جاتی ہیں.اور ذلت پانے والوں میں جو برائیاں موجود ہوتی ہیں وہ سب کی سب تم میں پائی جاتی ہیں.اب تم خود ہی سوچ سکتے ہو کہ ذلت کس کے حصہ میں آئے گی اور فتح کس کے حصہ میں.اس صورت میں وَالِدٍ وَّ مَا وَلَدَ سے مراد دنیا کے تمام باپ اور دنیا کی تمام اولادیں ہوں گی.یعنی تم اس دنیا پر غور کرو.لوگوں کے حالات پر تدبر کرو.ترقی و تنزل کے وجوہ پر نظر غائر ڈالو.تمہیں معلوم ہو گا کہ بعض خرابیاں باپ سے پیدا ہوتی ہیں اور بعض خرابیاں اولاد سے پیدا ہوتی ہیں.لیکن
Page 338
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم اور ان کی جماعت میں یہ دونوں باتیں نہیں پائی جاتیں.نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم میں وہ خرابیاں ہیں جو باپ میں موجود ہوتی ہیں.اور آئندہ نسل کو تباہ کر دیتی ہیں.نہ ان کے صحابہؓ میں وہ خرابیاں ہیں جو اولاد میں موجود ہوتی ہیں اور وہ باپ دادا کے نام کو ڈبو دیتی ہیں.پھر دنیا میں ترقی و تنزل کے حالات پر غور کرنے سے ان کی چار وجوہ معلوم ہوتی ہیں.یا تو باپ قابل ہوتا ہے لیکن بیٹا ناقابل ہوتا ہے.یا باپ ناقابل ہوتا ہے اور بیٹا قابل ہوتا ہے.یا باپ اور بیٹا دونوں ناقابل ہوتے ہیں یا باپ اور بیٹا دونوں قابل ہوتے ہیں.گویا یا تو دونوں قابل ہوں گے یا دونوں ناقابل ہوں گے.یا بیٹا قابل ہوگا اور باپ ناقابل یا باپ قابل ہوگا اور بیٹا ناقابل.ان چاروں صورتوں میں سے جب بیٹا قابل ہوتا ہے اور باپ ناقابل ہوتا ہے تو کبھی بیٹا اپنے باپ کے اثر کو قبول کر لیتا ہے اور کبھی نہیں کرتا اور آگے نکل جاتا ہے.کبھی باپ تو قابل ہوتا ہے.لیکن بیٹا نا قابل ہوتا ہے.ایسی صورت میں کبھی باپ کو ناکامی ہوتی ہے اور کبھی تربیت سے وہ اپنے بیٹے کو درست کر لیتا ہے.لیکن کبھی دونوں ناقابل ہوتے ہیں اور کبھی دونوں قابل ہوتے ہیں.جب باپ قابل ہو اور بیٹا ناقابل تو تربیت سے اس کے نقص کو دور کیا جا سکتا ہے.گو بعض دفعہ یہ نقص دور نہیں بھی ہوتا.جب باپ ناقابل ہو اور بیٹا قابل تو وہ کبھی باپ کے اثر کو مٹا کر کامیاب ہو جاتا ہے اور کبھی کسی پیدا کردہ الجھنوں میں دب کر خود بھی ہلاک ہو جاتا ہے.لیکن جب دونوں ناقابل ہوں تو اس وقت ترقی کا کوئی راستہ نہیں کھلتا.لیکن جب دونوں قابل ہوں تو اس وقت ان کا ترقی سے محروم رہنا ناممکن ہوتا ہے.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو دیکھ لو.باپ وہ ہے جو اپنے اندر ساری خوبیاں جمع رکھتا ہے اور بیٹے وہ ہیں جو ہر وقت اس کی اطاعت میں مشغول رہتے ہیں.اور جو بھی حکم ملے اس پر فوری طور پر عمل کرنے کے لئے کھڑے ہو جاتے ہیں.وہ تکالیف برداشت کرتے ہیں مشکلات میں سے گذرتے ہیں.مگر یہ پسند نہیں کرتے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم کے منہ سے کوئی بات نکلے تو وہ اس کے سننے سے محروم رہیں اور اس پر عمل کرنے میں پیچھے رہیں.چنانچہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ اس کی ایک شاندار مثال ہے.انہوں نے بہت بعد میں اسلام قبول کیا تھا.بیس سال رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم کے دعویٰ پر گذر چکے تھے کہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم کی بیعت میں شامل ہوئے اور اس کے تین سال بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم وفات پاگئے.وہ چونکہ جانتے تھے کہ بیس سال گذر چکے ہیں اور مجھے اسلام میں داخل ہونے کی بہت بعد میں توفیق ملی ہے.اس لئے جب انہوں نے بیعت کی تو اپنے دل میں یہ عہد کر لیا کہ اب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم
Page 339
کے دروازہ سے ہلوں گا نہیں سب لوگ اپنی اپنی جھولیاں بھر چکے ہیں صرف میں خالی ہاتھ ہوں.اگر میں نے ان ایام کو بھی ضائع کر دیا تو مجھے کیا ملے گا.چنانچہ اس عہد کے بعد وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم کے دروازہ پر بیٹھ گئے اور کچھ ایسے بیٹھے کہ ایک منٹ کے لئے بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم کی آنکھوں سے اوجھل ہونا انہیں ایک بلا اور عذاب معلوم ہوتا.وہ ہر وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم کے پاس بیٹھے رہتے.سوائے اس کے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں چلے جائیں.کیونکہ وہاں پردہ ہوا کرتا تھا.چونکہ وہ ہر وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کے دروازہ پر ہی بیٹھے رہتے تھے اور وہ ڈرتے تھے کہ اگر میں اِدھر اُدھر ہوا تو ایسا نہ ہو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کے منہ سے کوئی بات نکلے اور میں اسے سن نہ سکوں.اس لئے بسا اوقات انہیں کئی کئی دن کا فاقہ آ جاتا اور پھر شدت بھوک اور ضعف سے یہاں تک حالت ہو جاتی کہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر جاتے.لوگ سمجھتے کہ ان کو مرگی کا دورہ ہو گیا ہے اور وہ عرب کے دستور کے مطابق اس کے علاج کے لئے ان کے سر پر جوتیاں مارنے لگ جاتے.جب اسلامی فوجوں کے مقابلہ میں اللہ تعالیٰ نے کسریٰ کو شکست دی تو وہ رومال جس کو کسریٰ اپنے ہاتھ میں لے کر دربار شاہی میں تخت پر بیٹھا کرتا تھا.مال غنیمت میں تقسیم ہو کر حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کے حصہ میں آیا.ایک دفعہ وہ رومال ان کے ہاتھ میں تھا کہ انہیں کھانسی اٹھی بلغم آیا اور انہوں نے اسی رومال میں اس بلغم کو تھوک دیا.اور پھر کہا بَـخِّ بَـخِّ اَ بُوْھُرَیْرَۃَ واہ واہ ابو ہریرہ تیری بھی عجیب شان ہے کہ کسریٰ کا رومال تیرے ہاتھ میں ہے اور تو اس میں بلغم تھوک رہا ہے.لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا اس سے کیا مطلب.اس پر انہوں نے اپنا واقعہ سنایا اور بتایا کہ جب میں نے اسلام قبول کیا تو میں نے یہ عہد کر لیا کہ چونکہ میں بہت بعد میں شامل ہوا ہوں اس لئے اب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم کی صحبت کو چھوڑوں گا نہیں اور آپ کے دروازہ پر ہی بیٹھا رہوں گا خواہ مجھے کتنی تکلیف ہو.چنانچہ خدا نے مجھے اس عہد پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی.مگر میری حالت یہ تھی کہ بعض دفعہ مجھ پر سات سات وقت کا فاقہ آ جاتا اور پھر ضعف کی وجہ سے مجھے غشی کا دورہ ہوجاتا.صحابہؓ سمجھتے کہ مجھے مرگی ہوگئی ہے.عربوں میںر واج تھا کہ جب کسی کو مرگی کا دورہ ہوتا تو وہ اس کے سر پر جوتیاں مارتے اور سمجھتے کہ یہ اس مرض کا علاج ہے اور اس طرح مریض کو ہوش آ جاتا ہے.وہ کہتے ہیں جب میں بے ہوش ہوتا تو میرے سر پر بھی اس خیال کے ماتحت جوتیاں ماری جاتیں حالانکہ مجھے اندر سے ہوش ہوتا تھا.لیکن ضعف اس قدر غالب ہوتا تھا کہ بول نہیں سکتا تھا.مگر آج یہ حالت ہے کہ کسریٰ کا رومال میرے ہاتھ میں ہے اور میں اس میں اپنا بلغم تھوک رہا ہوں.
Page 340
اس واقعہ پر غور کرو اور دیکھو کہ کیسی تربیت یافتہ کیسی بااخلاق کیسی سمجھ دار اور کیسی قربانی کرنے والی اولاد اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم کو عطا کی تھی اور اس میں علم سیکھنے کا مادہ کس قدر انتہائی طور پر پایا جاتا تھا.غرض اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کامیابی کے اصول کے جتنے راستے دنیا میں پائے جاتے ہیں وہ سب کے سب اس باپ اور اس کے بیٹوں کو حاصل ہیں.اس لئے تمہیں اس بات میں کبھی شبہ ہی نہیں کرنا چاہیے کہ تمہاری شکست اور ان لوگوں کی فتح بالکل قطعی اور یقینی ہے.لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْ كَبَدٍؕ۰۰۵ ہم نے یقیناً انسان کو رہینِ محنت بنایا ہے.حلّ لُغات.اَلْکَبَدُ.اَلْکَبَدُ: اَلشِّدَّۃُ والْمَشَقَّۃُ یعنی کبد سختی اور مشقت کو کہتے ہیں.اسی طرح کَبَدٌ: وَسْطُ الرَّمْلِ یعنی ٹیلے کے درمیانی حصہ کو بھی کہتے ہیں اور کَبَدٌ کے معنے وَسْطُ السَّمَاءِ کے بھی ہیں.یعنی آسمان کے درمیان کو بھی کبد کہتے ہیں.اسی طرح کَبَدَ الرَّجُلُ کَبَدًا کے معنے ہوتے ہیں.اَ لِمَ مِنْ وَجَعِ کَبَدِہٖ وہ درد جگر میں مبتلا ہو گیا (اقرب) تفسیر.فرماتا ہے ہم نے انسان کو کبد میں بنایا ہے محاورہ کے لحاظ سے اس کے یہ معنے ہوں گے کہ ہم نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ وہ ہمیشہ تکلیف اور مشقت سے کام کرتا ہے.اسی طرح اس کے یہ بھی معنے ہیں کہ ہم نے انسان کو وسط سماء میں بنایا ہے.لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْ كَبَدٍ کے دومعنے پہلے معنوں کے رو سے اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے ہم نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ وہ محنت کرنے پر مجبور ہے.یہ گویا ایک لازمی بات ہے جس سے کوئی مفر نہیں.قدرت کا جو بھی کارخانہ ہے یا ہماری طرف سے جو قوتیں بھی بنی نوع انسان کو دی گئی ہیں.وہ لازمی طور پر اس بات کو ظاہر کرتی ہیں کہ ہم نے انسان کو محنت و کوشش کے لئے پیدا کیا ہے.میرے نزدیک یہ دوسرا جوابِ قسم ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم کی سچائی اور ان کی راستبازی کا ثبوت صرف وہی نہیں جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں.بلکہ اس کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم کی صداقت کا ایک یہ بھی ثبوت ہے کہ ہم نے انسان کو کبد میں پید اکیا ہے یعنی ہم نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ وہ محنت کرتا ہے اور محنت کرنے پر مجبور ہے یا وہ خدا کا ہو کر رہے گا یا دنیا کا.
Page 341
درمیان میں وہ لٹک نہیں سکتا اور نہ درمیانی انسان کبھی کامیاب ہو سکتا ہے.کامیابی یا عزت دو ہی طرح حاصل ہو سکتی ہے یا تو انسان دنیا کا ہو رہے، اگر خدا بھول گیا ہے تو دنیوی لحاظ سے محنت کرے، کوشش کرے، علم حاصل کرے، قربانی کرے اور اس طرح دنیا میں عزت حاصل کرے.اور یا پھر یہ طریق ہے کہ وہ خدا کا ہو جائے اور دنیا کی محبت اپنے دل سے بالکل مٹا دے اور دین کے لئے جدوجہدمیں لگ جائے.درمیانی راستہ اور کوئی نہیں.اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے.لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِیْ کَبَدٍ بغیر محنت دینی یا محنت دنیوی کے کوئی انسان عزت حاصل نہیں کر سکتا.حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے زمانہ میں تمام عزت خدا نے ہمارے ساتھ وابستہ کر دی ہے.اب عزت پانے والے یا ہمارے مرید ہوں گے یا ہمارے مخالف ہوں گے.چنانچہ فرماتے تھے مولوی ثناء اللہ صاحب کو دیکھ لو.وہ کوئی بڑے مولوی نہیں.ان جیسے ہزاروں مولوی پنجاب اور ہندوستان میں پائے جاتے ہیں.ان کو اگر اعزاز حاصل ہے تو محض ہماری مخالفت کی وجہ سے.وہ لوگ خواہ اس امر کا اقرار کریں یا نہ ،مگر واقعہ یہی ہے کہ آج ہماری مخالفت میں عزت ہے یا ہماری تائید میں گویا اصل مرکزی وجود ہمارا ہی ہے اور مخالفین کو بھی اگر عزت حاصل ہوتی ہے تو ہماری وجہ سے.چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے شہادت کے طور پر جن چیزوں کو پیش کیا ہے.ان کا وجود اس بات کا ایک اہم ثبوت ہے کہ ہم نے انسان کو محنت ومشقت سے کام لینے والا بنایا ہے.یہ مکہ جس میں تو رہتا ہے جس میں تجھے حلال سمجھا جانے والا ہے.جس میں تجھے ہر تیر کا نشانہ بنایا جانے والا ہے.جس میں تیری ایذا دہی کی ہر ممکن کوشش ہونے والی ہے اور جس میں تیری جان کی کوئی قدر و قیمت نہیں سمجھی جائے گی.یہ ہمارے اس دعویٰ کا ثبوت ہے اس لئے کہ تجھے مارنے اور تباہ کرنے کی وہ جتنی بھی کوشش کریں گے ان میں انہیں ناکامی ونامرادی حاصل ہو گی اور انہیں آخر اس حقیقت کا اعتراف کرنا پڑے گا کہ ان کی کوشش اور کارنامے نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوئے.ان کی یہ ناکامی اپنی ذات میں اس بات کا ایک ثبوت ہو گی کہ انسان کو ہم نے ایسا ہی بنایا ہے کہ سچی محنت کے بغیر وہ کامیاب نہیں ہو سکتا.ان کی مخالفتیں بالکل سطحی ہیں.اور ان کی کوششیں بالکل عبث.کیونکہ وہ حقیقی قربانی سے کام نہیں لے رہے وہ سمجھتے ہیں جو بڑا بننے والا ہو اس کو مار دینا چاہیے.حالانکہ مارنے سے کیا بنتا ہے.بڑا انسان تب بنتا ہے جب وہ قربانی سے کام لے.مگر تمہاری یہ حالت ہے تم یتیموں کو پوچھتے نہیں، تم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے، تم اپنے مالوں کو قومی اور ملی مفاد کے لئے قربان نہیں کرتے، تمہیں جائیدادیں ملتی ہیں تو تم انہیں تباہ برباد کر دیتے ہو.گویا جس قدر بنیادی کام ہیں اور جو محنت و مشقت اور قربانی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں.ان کو تو تم سرانجام نہیں
Page 342
دیتے.ا ور جو شخص ان کاموں کو کرنے لگے اسے مارنے کے لئے دوڑ پڑتے ہو اس سے کیا بن سکتا ہے.تم یاد رکھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم کو خواہ تم مارنے کی کتنی بھی کوشش کرو وہ کبھی نہیں مرے گا.بلکہ تم ہی مرو گے.اور یہ ثبوت ہو گا اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام تر عزت قربانی میں رکھی ہے.جب کوئی شخص اپنے جگر کا خون کر کے آگے بڑھنا چاہے تو اللہ تعالیٰ اسے عزت دے دیتا ہے.لیکن وہ جو سہل ترین راستہ پر چلنے کی کوشش کریں جو قربانیوں میں حصہ لینے سے دل چرائیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے.پس فرمایا تم اپنا روشن مستقبل کس طرح مانتے ہو جب کہ تم میں کبد والی حالت ہی نہیں.کبد والی حالت تو تقاضا کرتی ہے کہ انسان یاخدا کا ہو کر رہے یا دنیا کا.مگر تم نہ خدا کے ہو نہ دنیا کے.نہ تم میں مذہب ہے نہ قومی اخلاق ہیں.اور جب حالت یہ ہے تو تمہارا مستقبل کس طرح روشن ہوسکتا ہے.اس آیت کے یہ معنے بھی ہو سکتے ہیں کہ ہم نے انسان کو وسط سماء میں پیدا کیا ہے.سماء سے مراد وہ بلند اخلاق ہوں گے جو انسان کے روحانی ارتقاء کے لئے ضروری ہیں اور وسط کے معنی تو ہر شخص جانتا ہی ہے کہ درمیان کے ہوتے ہیں پس لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِیْ کَبَدٍ کے معنے یہ ہوئے کہ کامل انسان وہی ہوتا ہے اور بااخلاق وہی کہلا سکتا ہے جس کے اندر اعتدال موجود ہو اور وسطی اخلاق اس کے اندر پائے جائیں.گویا اوّل اس کا سماء سے تعلق ہو اور پھر اس کے اخلاق وسطی رنگ کے ہوں وہ ایک طرف جھکا ہوا نہ ہو.وسط سماء میں پیدا کرنے کے یہ معنے بھی ہوسکتے ہیں کہ جب تک اس کا شرعی اور قدرتی قواعد سے تعلق نہ ہو گا کامیاب نہیں ہو سکتا.دونوں کا پورا کرنا ضروری ہے.یعنی جب تک اس میں اعتدال نہ ہو گا کامیاب نہیں ہو سکے گا.اَيَحْسَبُ اَنْ لَّنْ يَّقْدِرَ عَلَيْهِ اَحَدٌۘ۰۰۶ کیا وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس پر کسی کا زور نہ چلے گا.تفسیر.یہاں وہ انسان مراد نہیں جسے خدا تعالیٰ نے کبد والی حالت میں پیدا کیا ہے بلکہ یہاں انسان سے مراد اس کا ناقص وجود ہے.فرماتا ہے کیا گمان کرتا ہے وہ شخص جو ظاہر میں تو انسان کہلاتا ہے مگر حقیقت میں انسانیت سے بہت دور اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل میں کھڑا ہے کہ خواہ وہ کبد کے مقام کو چھوڑ بیٹھے اور شرعی اور دنیوی دونوں قواعد سے بے نیاز ہو کرکام کرے پھر بھی اس پر کوئی تنگی نہیں آئے گی یہ بالکل غلط ہے.
Page 343
ہم نے انسان کو فِيْ كَبَدٍ کے مقام پر پیدا کیا ہے.مگر وہ اوّل تو اخلاق کو چھوڑ بیٹھتا ہے اور پھر اگر اس میں کوئی پہلو اخلاق نما پایا بھی جاتا ہے تو وہ غلو کی صورت اختیار کر کے ایک بدی بن جاتا ہے مثلاً ضرورت حقہ پر مال خرچ کرنا، یتامیٰ و مساکین کی خبر گیری کرنا یہ اخلاق سے تعلق رکھنے والے افعال ہیں.مگر وہ اس رنگ میں مال خرچ نہیں کرتا بلکہ جو کچھ آتا ہے اسراف سے کام لے کر تباہ و برباد کر دیتا ہے.اس مقام پر کھڑے ہو کر بھی کیا وہ سمجھتا ہے کہ میرے اوپر خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی تنگی نہیں آ سکتی.کوئی تباہی اور بربادی مجھ پر مسلط نہیں ہو سکتی.جو شخص ایک غلط مقام پر کھڑا ہو جاتا ہے اور جس مقام کے لئے اسے پیدا کیا گیا تھا اسے بھول جاتا ہے.وہ کس طرح سمجھ سکتا ہے کہ الٰہی گرفت سے وہ بچ جائے گا.لازماً وہ اپنی اس بے اعتدالی کے نتیجہ میں ایک دن تکلیف میں مبتلا ہو گا.مصیبت میں گرفتار ہو گا اور خدا کے فضل کی بجائے اس کا عذاب اپنے اوپر نازل ہوتے دیکھے گا.يَقُوْلُ اَهْلَكْتُ مَالًا لُّبَدًاؕ۰۰۷ وہ کہتا ہے کہ میں نے تو ڈھیروں ڈھیر مال لٹا دیا ہے.حلّ لُغات.لُبَدٌ.لُبَدٌ کے معنے ہوتے ہیں.کَثِیْرٌ لَا یُـخَافُ فَنَاؤُہٗ کَاَنَّہُ الْتَبَدَ بَعْضُہٗ عَلٰی بَعْضٍ.اتنا زیادہ مال کہ اس کے ختم ہونے کا خوف نہ ہو.گویا وہ ایک ڈھیر کے اوپر دوسرا ڈھیر ہے (اقرب) گویا لُبَدٌ کے معنے ہیں ڈھیروں ڈھیر مال.تفسیر.کہتا ہے تم یہ کیا کہتے ہو کہ میں نے مال خرچ نہیں کیا.میں نے تو ڈھیروں ڈھیر مال خرچ کیا ہے اور لوگ اس بات پر گواہ ہیں مگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں نے کوئی مال خرچ ہی نہیں کیا.اَيَحْسَبُ اَنْ لَّمْ يَرَهٗۤ اَحَدٌؕ۰۰۸ کیا وہ سمجھتا ہے کہ اسے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے.تفسیر.فرماتا ہے کیا وہ خیال کرتا ہے کہ نہ اوپر خدا اس کے افعال کو دیکھنے والا ہے.نہ بندے اس کے اعمال پر نظر رکھتے ہیں اور وہ جو کچھ کہے گا اسے درست تسلیم کر لیا جائے گا.خدا تو انسان کا دل دیکھتا ہے.کیونکہ دل کی درستی بھی ترقی کے لئے ضروری ہوتی ہے.وہ کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں ڈھیر مال خرچ کیا ہے.مگر کیا خدا
Page 344
نہیں جانتا کہ اس نے یہ ڈھیروں ڈھیر مال کیوں خرچ کیا ہے.یا کیا بندے نہیں جانتے کہ اس نے اتنا روپیہ کیوں صرف کیا ہے.فرماتا ہے تو نے بےشک اپنا مال خرچ کیا ہے.مگر سوال تو یہ ہے کہ تو نے اپنا مال کس جگہ پر خرچ کیا ہے.ہم مان لیتے ہیں کہ تم نے اپنا سارا مال لٹا دیا ہے.لیکن اگر تم ان لوگوں میں سے ہو جو تَاْکُلُوْنَ التُّرَاثَ اَکْلًا لَّمًّا.وَّتُحِبُّوْنَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا کے مصداق ہیں تو بتاؤ تم اللہ تعالیٰ کے حضور کون سی فضیلت پا سکتے ہو.یا کم از کم بنی نوع انسان کی نگاہ میں ہی تمہیں کون سا مقام حاصل ہو سکتا ہے.نہ خدا تم کو فضیلت دے گا اور نہ بندے تمہارا ادب کریں گے کیونکہ خدا بھی جانتا ہے اور اس کے بندے بھی جانتے ہیں کہ تم نے محض نام آوری کے لئے، محض جاہ طلبی اور شہرت کے حصول کے لئے یہ سب کچھ کیا.تمہیں بعض دفعہ جوش آ جاتا تو تم سو سو اونٹ ایک ایک دن میں ذبح کر دیتے.مگر سوال یہ ہے کہ ان اونٹوں کے ذبح کرنے کا کیا فائدہ تھا جب کہ یتیم بھوکے مرتے رہے اور تم نے انہیں کھانا نہ کھلایا.مساکین ننگے پھرتے رہے اور تم نے انہیں کپڑا نہ پہنایا.حاجت مند پریشان رہے اور تم نے ان کی حاجات کو پورا نہ کیا.اگر تمہارے دل میں بنی نوع انسان کی کچھ بھی محبت ہوتی اور اگر ان کے فقر و فاقہ کی مصیبت تمہارے دل کو کچھ بھی متاثر کرتی تو بجائے اس کے کہ ایک ایک دن میں تم سو سو اونٹ ذبح کر دیتے.تم ان کی امداد کے لئے یہ طریق اختیار کرتے کہ ایک اونٹ ذبح کیا اور ان کو کھلا دیا.پھر کوئی اونٹ ذبح کیا اور ان کو کھلا دیا.اس طرح تم تین بلکہ چھ ماہ تک اپنی اس امداد کے سلسلہ کو ممتد کر دیتے.مگر تمہارے مدّ ِنظر تو یہ بات تھی کہ لوگوں میں تمہاری شہرت ہو.لوگ دور دور سے اونٹوں پر سوار ہو کر تمہاری دعوت میں شریک ہونے کے لئے آئیں اور جب لوگ ان سے پوچھیں کہ آج تم کہاں جا رہے ہو تو وہ بتائیں کہ فلاں امیر کے ہاںدعوت ہے.اس نے آج سو اونٹ ذبح کئے ہیں.اس دعوت میں شمولیت کے لئے ہم جا رہے ہیں.جب تمہارے مدّ ِنظر محض جاہ طلبی اور لوگوں میں اپنی عزت کو بڑھانا اور دور دور تک مشہور ہونا تھا تو بتاؤ خدا تمہاری کیوں قدر کرے.یا بنی نوع انسان تمہارا کیوں احترام کریں.کیا لوگ اندھے ہیں کہ وہ اتنی موٹی بات کو بھی نہیں سمجھ سکتے کہ تم نے جو کچھ کیا ہے ان کی خاطر نہیں کیا بلکہ اپنے نفسوں کی خاطر کیا ہے.یا کیا خدا تمہارے دلوں کی نیتوں سے آگاہ نہیں اور وہ نہیں جانتا کہ تمہارے پیش نظر کیا مقصد تھا.پس فرمایا اَيَحْسَبُ اَنْ لَّمْ يَرَهٗۤ اَحَدٌ کیا یہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ انہیں نہ خدا دیکھتا ہے اور نہ اس کے بندے دیکھتے ہیں.وہ مال تو عزت طلبی کے لئے خرچ کر رہا ہے.شہر ت کے حصول کے لئے برباد کر رہا ہے اور توقع یہ رکھتا ہے کہ لوگ مجھے اپنا محسن سمجھیں.آخر لوگ اسے کیوں سمجھیں کیا وہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہےکہ وہ جو کچھ کر رہا ہے دنیا کے لئے کر رہا ہے.کیونکہ وہ مال اس طرح خرچ نہیں
Page 345
کرتا کہ اس کے خرچ سے زیادہ سے زیادہ آدمیوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے.اور جب واقعہ یہی ہے تو پھر خدا اور اس کے بندوں کی نگاہ میں اس کی کیا عزت ہو سکتی ہے.اَلَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ عَيْنَيْنِۙ۰۰۹وَ لِسَانًا وَّ شَفَتَيْنِۙ۰۰۱۰ کیا ہم نے اس کے لئے دو آنکھیں نہیں پیدا کیں.اور زبان بھی اور دو ہونٹ بھی.تفسیر.فرماتا ہے اس امر کو اچھی طرح یاد رکھو کہ تمہارا معاملہ خدا کے ساتھ ہے.اور خدا تعالیٰ سچے عذر کو ضرور قبول کر لیا کرتا ہے.اگر تمہارا سچا عذر ہوتا تو اللہ تعالیٰ تمہیں یقیناً تباہ نہ کرتا اور وہ سچا عذر یہی ہوتا ہے کہ انسان کی آنکھیں نہ ہوں اور اسے کچھ دکھائی نہ دیتا ہو.یہ لازمی بات ہے کہ جس کی آنکھوں میں بینائی نہیں ہو گی.اس کے سامنے اگر کوئی گڑھا آئے گا تو وہ ضرور اس میں گر جائے گا.مگر کوئی شخص ایسا نہیں ہو گا جو اسے یہ کہے کہ خبیث کیوں تو اس گڑھے سے بچ کر نہ چلا.ہر شخص کہے گا کہ جب اس کی آنکھیں ہی نہیں تھیں تو اگر یہ گڑھے میں گر گیا ہے تو معذور ہے.یا اگر ایک شخص راستہ بھول گیا ہے مگر وہ گونگا ہے لوگوں سے یہ دریافت نہیں کر سکتا کہ سیدھا راستہ کون سا ہے تو کوئی شخص اسے ملامت نہیں کرے گا کہ تو راستہ لوگوں سے پوچھ کر کیوں نہ چلا.ہر شخص سمجھے گا کہ یہ معذور تھا.یہ کسی سے راستہ پوچھ نہ سکتا تھا.یا اگر کسی کی آنکھیں بھی ہوں، زبان بھی موجود ہو مگر کوئی راستہ بتانے والا نہ ہو اور وہ چلتے چلتے شیروں کی کچھار میں پہنچ جائے یا ہاتھیوں کی وادی میں چلا جائے اور شیر اس کو پھاڑ ڈالیں یا ہاتھی اس کو مسل ڈالیں تب بھی وہ معذور سمجھا جائے گا.لوگ کہیں گے کہ اس کی آنکھیں تو تھیں جن سے راستہ دیکھ سکتا.زبان بھی تھی جس سے کام لے کر لوگوں سے رستہ دریافت کر سکتا مگر چونکہ اسے کوئی صحیح رستہ بتانے والا نہیں ملا اس لئے وہ ٹھوکر کھا کر کہیں کا کہیں پہنچ گیا.بہرحال وہ معذور اسی صورت میں سمجھا جا سکتا ہے جب وہ بوجہ آنکھیں اور زبان نہ ہونے کے رستہ دیکھنے یا دریافت کرنے سے معذور ہو یا رستہ بتانے والا کوئی شخص موجود نہ ہو.مگر ان تمام جائز اور صحیح اور معقول عذرات کے باوجود دنیا کا قانون اسے عواقب سے بچا نہیں سکتا.ایک انسان اندھا ہوتا ہے اور وہ دن کے وقت یا رات کی تاریکی میں کسی گڑھے میں گر جاتا ہے وہ اس گرنے میں معذور ہوتا ہے.مگر کوئی مادی قانون اسے گڑھے میں گرنے سے بچاتا نہیں یا ایک گونگا ہوتا ہے اور وہ راستہ پوچھ نہیں سکتا.اس کے نتیجہ میں وہ ایک غلط راستہ پر چل
Page 346
پڑتا ہے.وہ اپنی اس غلطی میںقطعی طور پر معذور ہوتا ہے مگر مادی دنیا کا قانون اسے راستہ بھولنے کی سزا سے نہیں بچا سکتا یا ایک شخص کی آنکھیں بھی ہوتی ہیں، اس کی زبان بھی موجود ہوتی ہے مگر اسے کوئی راستہ بتانے والا نظر نہیں آتا اور وہ ٹھوکر کھا کر شیروں کی کچھار میں پہنچ جاتا ہے.اب بے شک وہ اپنے اس فعل میں معذور ہوتا ہے مگر نیچر کا قانون اسے تکلیف سے نہیں بچا سکتا.یہ نہیں ہوتا کہ نیچر اسے شیروں کی کچھار سے پرے پھینک دے.یا دھکے دے کر ہاتھیوں کے حملہ سے اسے بچالے.لیکن فرمایا روحانی معاملہ اور رنگ کا ہوتا ہے.اس میں عذر قبول کیا جاتا ہے.ایک اندھا گرتا ہے تو باوجود معذور ہونے کے وہ گڑھے میں گرنے کی تکلیف سے نہیں بچتا.ایک گونگا راستہ نہیں پائے گا تو باوجود معذور ہونے کے وہ راستہ میں ٹھوکریں کھانے کی تکلیف سے نہیں بچتا.ایک شخص آنکھیں بھی رکھتا ہے اور زبان بھی مگر چونکہ اسے راستہ بتانے والا کوئی نہیں ملتا وہ شیروں کی کچھار میں پہنچ جاتا ہے اور باوجود معذور ہونے کے اس کی یہ معذوری اسے موت کے پنجہ سے نہیں بچا سکتی.لیکن فرمایا ہم اس قسم کے تمام حقیقی عذرات کو قبول کر لیا کرتے ہیں.اگر لوگ روحانی آنکھوں سے معذور ہوتے تو ہم کہتے کہ وہ معذور تھے انہیں کوئی سزا نہ دی جائے.اگر لوگ روحانی امور میں گویائی کی طاقت نہ رکھتے تو ہم بھی قرار دیتے کہ وہ معذور ہیں انہیں عذاب نہ دیا جائے.اگر کوئی ہادی نہ آتا تب بھی ہم لوگوں کو معذور قرار دیتے.پس اے مکہ والو! اگر تم میں کوئی ایسا قانون موجود نہ ہوتا جو تمہیں ہدایت اور راستی کی طرف لاتا اور تم اِدھر اُدھر ویسے ہی بھٹک رہے ہوتے.جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم کے آنے سے پہلے بھٹک رہے تھے.تو ہم کہتے مکہ بلد الحرام ہے.اس کے رہنے والے ہماری نگاہ میں معذور ہیں.ان کو ہماری طرف سے کوئی ہدایت نہیں ملی.ان کو کوئی سزا نہ دی جائے.مگر تمہاری حالت تو یہ ہے کہ تمہاری آنکھیں بھی موجود ہیں.تمہاری زبان بھی موجود ہے.تمہارے سامنے ایک ترقی کا راستہ بھی موجو د ہے.تمہیں اس ترقی کے راستہ پر چلانے والا بھی موجود ہے اور تم پھر بھی گمراہی کو اختیار کئے ہوئے ہو.ان حالات میں تم خود ہی غور کرو کہ تم عذاب الٰہی سے کس طرح بچ سکتے ہو.اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہلاکت سے بچنے کے تین ذرائع بتائے ہیں.اوّل آنکھیں دیکھنے کے لئے دوم زبان اور ہونٹ پوچھنے کے لئے.سوم ترقی کار استہ یعنی کامیابی کےلئے یہ تین چیزیں ضروری ہوتی ہیں.مقصد صحیح ہو اور ترقی کا موجب بن سکے آنکھوں سے دیکھ کر کام کرے اور نہ معلوم ہو سکے تو پوچھے.پھر ان کے لئے کیا مشکل تھا کہ ترقی کر جاتے.آنکھیں خدا تعالیٰ نے دیکھنے کو دی تھیں.زبان خدا تعالیٰ نے پوچھنے کو دی تھی.صرف راستہ غائب تھا سو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم نے وہ راستہ جو اوپر لے جاتا ہے دکھا دیا.
Page 347
اس کے بعد ان کا کیا عذر رہ جاتا ہے.زبان کے ساتھ ہونٹوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس لئے کیا ہے کہ ہونٹ ہوا کو روکتے ہیں اور انسانی آواز کو بلند کرتے ہیں.جس شخص کے دانت نکل جائیں وہ اونچی آواز سے نہیں بول سکتا.میرا صرف ایک دانت نکلا ہوا ہے مگر جب میں تقریر کر رہا ہوتا ہوں تو مجھے بعض دفعہ محسوس ہوتا ہے کہ اس خلا میں سے پھونک نکل جاتی ہے اور کسی کسی لفظ کا تلفظ صحیح طور پر ادا نہیں ہوتا.حضرت خلیفۂ اوّل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ موٹے ہونٹوں کو ناپسند کرتے ہیں مگر میرے لئے تو موٹے ہونٹ خدا تعالیٰ کی ایک بہت بڑی رحمت کا موجب بن گئے ہیں.میرے دانت سب گر چکے ہیں مگر موٹے ہونٹوں کی وجہ سے میں اب بھی خوب اونچی آواز سے بول سکتا ہوں تو فرمایا ہم نے انسان کو بولنے کے لئے زبان دی اور پھر ہم نے اسے ہونٹ بھی دیئے تاکہ اگر سامع اس کے قریب نہ ہو تو وہ دور تک اپنی آواز پہنچا سکے.وَ هَدَيْنٰهُ النَّجْدَيْنِۚ۰۰۱۱ اور (پھر) ہم نے اسے (دینی ودنیوی) دونوں راستے بھی تو بتا دیئے ہیں.تفسیر.نَـجْدٌ.نَـجْدٌ کے معنے پہاڑی راستہ کے ہوتے ہیں.لیکن مفسرین نے اس سے برائی اور بھلائی کا راستہ مراد لیا ہے.چنانچہ حضرت ابن عباسؓ اور ابن مسعودؓ دونوں نے کہا ہے کہ اس جگہ نَـجْدَیْنِ سے خیر اور شر دو۲ راستے مراد ہیں اور آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے انسان کو بھلائی کا راستہ بھی بتا دیا اور برائی کا راستہ بھی بتا دیا مگر اس نے اچھے راستے کو اختیار نہیں کیا.نجدین سے مراد بھلائی اور برائی کے دو راستے میری رائے یہ ہے کہ یہاں نَـجْدَیْن سے بھلائی اور برائی کے راستے مراد نہیں بلکہ دینی اوردنیوی ترقی کے راستے مراد ہیں.شر کا راستہ اونچا نہیں کہلا سکتا.کیونکہ نہ اس کے اختیار کرنے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے اور نہ اس راستہ پر چل کر کوئی عزت ملتی ہے اور راستہ اونچا انہی دو سبب سے کہلاتا ہے.اس پر چڑھنے میں تکلیف ہو یا اس پر چڑھ کر صحیح عزت ملے.پس یہاں نَـجْدَیْن سے خیر اور شر مراد نہیں.بلکہ مراد یہ ہے کہ ہم نے انسان کی ترقی کے لئے دونوں قسم کے راستے کھول دئیے ہیں اس کی دینی ترقی کے راستے بھی کھولے ہوئے ہیں اور اس کی دنیوی ترقی کے راستے بھی کھولے ہوئے ہیں.اور یہ دونوں
Page 348
راستے ہم نے محمد صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم کے ذریعہ کھولے ہیں.جو لوگ آپ پر سچے دل سے ایمان لائیں گے اور اسلام کے تمام احکام کی خلوصِ دل کے ساتھ اتباع کریں گے انہیں نہ صرف روحانی ترقی حاصل ہو گی اور اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے خدا تعالیٰ ان سے خوش ہو گا بلکہ اللہ تعالیٰ ا نہیں دنیوی نعماء سے بھی متمتع فرمائے گا چنانچہ دیکھ لو محمد صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم کے صحابہؓ کو صرف دین ہی نہیں ملا بلکہ دنیا بھی ملی اور آخر حکومت کی باگ ڈور اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں دے دی.یہی بات اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمائی ہے کہ آج تم محمد صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم پر ایمان لانے والوں کو دیکھتے ہو تو حقارت کی ہنسی ہنستے ہوئے کہتے ہو کہ چند بےوقوف نوجوان ہیں جو اس پر ایمان لے آئیں ہیں.مگر تم نہیں جانتے کہ یہی نوجوان جن کو تم بے وقوف قرار دے رہے ہو جن کو تم نہایت ذلیل اور حقیر وجود سمجھتے ہو.ایک دن محمد صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم پر ایمان لانے کی برکت سے دنیا کے بادشاہ بن جائیں گے اور دینی اور دنیوی دونوں ترقیات کے راستے ان کے لئے کھل جائیں گے.چنانچہ ایک دن آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس وعدہ کے مطابق صحابہؓ کو بادشاہت دے دی.اور اس طرح دونوں نجد ان کو مل گئے.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے لئے بھی اسلام کی اتباع میں دینی اور دنیوی دونوں ترقیات تھیں.اخلاقی راستہ پر چل کر خدا تعالیٰ کا خوش ہونا اور قوم کی خدمت کی وجہ سے شیرازہ بندی اور سیاست کی مضبوطی کا حاصل ہونا.دونوں قطعی اور یقینی امور تھے.مگر باوجود اس کے کہ ہم نے تمہیں آنکھیں دی تھیں، تمہیں زبان دی تھی، تمہارے سامنے اسلام کے ذریعہ دینی اور دنیوی ترقیات کا ایک بہت بڑا میدان تیار کیا تھا.پھر بھی تم نے اس راستہ کو اختیار نہ کیا جو تمہیں کامیابی کی منزل کی طرف لے جاتا بلکہ تم اسی راستہ کی طرف جھکے رہے جو ہلاکت و تباہی وبربادی کا تھا.فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَٞۖ۰۰۱۲ (مگر) وہ پھر بھی چوٹی پر نہ چڑھا.حلّ لُغات.اِقْتِحَامٌ.اِقْتِحَامٌ کے معنے نتائج سے بے فکر ہو کر اور عواقب کو نظر انداز کرکے کسی کام میں مشغول ہو جانے کے ہوتے ہیں.چنانچہ لغت میں لکھا ہے اِقْتَحَمَ الْعَقَبَۃَ: رَمٰی نَفْسَہٗ فِیْـھَا بِشِدَّۃٍ وَّمَشَقَّۃٍ.کسی کھائی میں داخل ہونے کے لئے یا کسی معاملہ میں اپنے آپ کو سختی سے ڈال دیا.اسی طرح قَـحَمَ فِی الْاَمْرِ کے معنے ہوتے ہیں.رَمٰی بِنَفْسِہٖ فِیْہِ فَـجْأَۃً بِلَا رَوِیَّۃٍ بغیر سوچنے کے جس طرح پروانہ شمع پر جاگرتا ہے
Page 349
راستے ہم نے محمد صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم کے ذریعہ کھولے ہیں.جو لوگ آپ پر سچے دل سے ایمان لائیں گے اور اسلام کے تمام احکام کی خلوصِ دل کے ساتھ اتباع کریں گے انہیں نہ صرف روحانی ترقی حاصل ہو گی اور اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے خدا تعالیٰ ان سے خوش ہو گا بلکہ اللہ تعالیٰ ا نہیں دنیوی نعماء سے بھی متمتع فرمائے گا چنانچہ دیکھ لو محمد صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم کے صحابہؓ کو صرف دین ہی نہیں ملا بلکہ دنیا بھی ملی اور آخر حکومت کی باگ ڈور اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں دے دی.یہی بات اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمائی ہے کہ آج تم محمد صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم پر ایمان لانے والوں کو دیکھتے ہو تو حقارت کی ہنسی ہنستے ہوئے کہتے ہو کہ چند بےوقوف نوجوان ہیں جو اس پر ایمان لے آئیں ہیں.مگر تم نہیں جانتے کہ یہی نوجوان جن کو تم بے وقوف قرار دے رہے ہو جن کو تم نہایت ذلیل اور حقیر وجود سمجھتے ہو.ایک دن محمد صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم پر ایمان لانے کی برکت سے دنیا کے بادشاہ بن جائیں گے اور دینی اور دنیوی دونوں ترقیات کے راستے ان کے لئے کھل جائیں گے.چنانچہ ایک دن آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس وعدہ کے مطابق صحابہؓ کو بادشاہت دے دی.اور اس طرح دونوں نجد ان کو مل گئے.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے لئے بھی اسلام کی اتباع میں دینی اور دنیوی دونوں ترقیات تھیں.اخلاقی راستہ پر چل کر خدا تعالیٰ کا خوش ہونا اور قوم کی خدمت کی وجہ سے شیرازہ بندی اور سیاست کی مضبوطی کا حاصل ہونا.دونوں قطعی اور یقینی امور تھے.مگر باوجود اس کے کہ ہم نے تمہیں آنکھیں دی تھیں، تمہیں زبان دی تھی، تمہارے سامنے اسلام کے ذریعہ دینی اور دنیوی ترقیات کا ایک بہت بڑا میدان تیار کیا تھا.پھر بھی تم نے اس راستہ کو اختیار نہ کیا جو تمہیں کامیابی کی منزل کی طرف لے جاتا بلکہ تم اسی راستہ کی طرف جھکے رہے جو ہلاکت و تباہی وبربادی کا تھا.فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَٞۖ۰۰۱۲ (مگر) وہ پھر بھی چوٹی پر نہ چڑھا.حلّ لُغات.اِقْتِحَامٌ.اِقْتِحَامٌ کے معنے نتائج سے بے فکر ہو کر اور عواقب کو نظر انداز کرکے کسی کام میں مشغول ہو جانے کے ہوتے ہیں.چنانچہ لغت میں لکھا ہے اِقْتَحَمَ الْعَقَبَۃَ: رَمٰی نَفْسَہٗ فِیْـھَا بِشِدَّۃٍ وَّمَشَقَّۃٍ.کسی کھائی میں داخل ہونے کے لئے یا کسی معاملہ میں اپنے آپ کو سختی سے ڈال دیا.اسی طرح قَـحَمَ فِی الْاَمْرِ کے معنے ہوتے ہیں.رَمٰی بِنَفْسِہٖ فِیْہِ فَـجْأَۃً بِلَا رَوِیَّۃٍ بغیر سوچنے کے جس طرح پروانہ شمع پر جاگرتا ہے
Page 350
وَ مَاۤ اَدْرٰىكَ مَا الْعَقَبَةُؕ۰۰۱۳فَكُّ رَقَبَةٍۙ۰۰۱۴ اور تجھے کس نے بتایا ہے کہ چوٹی کیا (اور کس چیز کا نام) ہے.(چوٹی پر چڑھنا غلام کی)گردن چھڑانا ہے.حلّ لُغات.فَکُّ رَقَبَۃٍ.فَکٌّ کے معنے کھول دینے کے ہوتے ہیںاور رَقَبَۃٌ کے معنے گردن کے ہیں.پس فَکُّ رَقَبَۃٍ کے معنے ہوئے گردن آزاد کرنا.یعنی کسی غلام کو آزاد کرانے میں مدد دینی.تفسیر.اس آیت کے دو۲ معنے ہیں.ایک تو یہ کہ انہیں چاہیے تھا وہ غلام آزاد کروانے کی کوشش کرتے.اگر یہ ان غلاموں کو جوان کے پاس ہیں آزاد کروانے کی کوشش کرتے تو یہ خود بھی قومی لحاظ سے آزادی حاصل کر سکتے تھے.مگر یہ الٹا غلامی کو اور بھی رائج کرنے لگیں گے اور مسلمان غلاموں پر ظلم ڈھانے لگ جائیں گے.درحقیقت غلاموں کی آزادی کا اسلام نے شروع سے ہی اس لئے حکم دیا ہے کہ قومی ترقی کے لئے غلاموں کا آزاد کرنا نہایت ضروری ہوتا ہے.مساوات قائم کئے بغیر اور چھوٹوں بڑوں کا امتیاز مٹائے بغیر دنیا میں کبھی کوئی قوم ترقی نہیں کیا کرتی.جب تک یہ امتیاز دنیا میں نظر آتا رہے گا کہ ایک چھوٹا ہے اور ایک بڑا اس وقت تک دنیا حقیقی ترقی نہیں کر سکتی.کبھی کوئی پائدار امن قائم نہیں ہو سکتا جب تک دنیا میں یہ فتنے موجود رہیں گے اور جب تک ان کے انسداد کے لئے متحدہ مساعی عمل میں نہیں لائی جائیں گی اس وقت تک ترقی کی تمام تدابیر بے کار ثابت ہوں گی.اسی امتیاز کا نتیجہ غلامی ہے جس کی بیخ کنی اسلام کا اولین مقصد ہے اور جس کے خلاف وہ شروع دن سے اپنی آواز کو بلند کر رہا ہے اگر ان امتیازات کو قائم رہنے دیا جائے تو بڑے آدمی اپنے لئے اور عزت چاہتے ہیں.پھر اور عزت کے طلب گار ہوتے ہیں.پھر اور عزت کا حصول ان کو بے قرار رکھتا ہے.یہاں تک کہ ایک دن ایسا آتا ہے جب وہ اپنے سوا کسی اور کو بڑا سمجھنے کے لئے تیار ہی نہیں ہوتے.میں نے دیکھا ہے ہندوستان کے ایک بہت بڑے لیڈر ہیں.میں ان کا نام نہیں لیتا.ان کے دماغ میں یہ خیال سمایا ہوا ہے کہ ان سے بڑا لیڈر اور کوئی نہیں.یہی دُھن انہیں آٹھوں پہر رہتی ہے اور اپنی بڑائی اور اعزاز کا خیال انہیں ہر وقت دامنگیررہتا ہے.ایک دفعہ شملہ میں ہندوستان کے بڑے بڑے لیڈروں کی ایک مجلس منعقد ہوئی.مجھے بھی تار دے کر بلایا گیا.گاندھی جی نے اس وقت مرن برت رکھا ہوا تھا اور انہو ں نے کہا تھا کہ اگر ہندو مسلم اتحاد نہ ہوا تو میں بھوکا مر جاؤں گا چونکہ یہ بڑا بھاری مسئلہ تھا.سارے ہندوستان سے مختلف اقوام کے لیڈر شملہ میں جمع ہوئے.میں سمجھتا ہوں ان کی تعداد سو ڈیڑھ سو کے قریب ہو گی.کوئی بمبئی سے آیا، کوئی مدراس سے،
Page 351
کوئی سی پی سے، کوئی بنگال سے، کوئی بہار سے، کوئی اڑیسہ سے، کوئی سرحد سے، کوئی ریاستوں سے.غرض ایک اچھا خاصہ اجتماع ہندوستان کے تمام لیڈروں کا شملہ میں جمع ہو گیا.جب ان لیڈر صاحب نے اتنا بڑا مجمع دیکھا تو چونکہ انہیں صرف اپنی لیڈری کو ظاہر کرنے کی عادت تھی.کسی اور لیڈر کو لیڈر سمجھنا وہ اپنی ہتک سمجھتے تھے.اس لئے جب وہ تقریر کے لئے کھڑے ہوئے تو میں نے دیکھا کہ وہ بار بار کہتے کہ ایسے اہم مسائل کے متعلق کبھی ہجوم فیصلہ نہیں کیا کرتے.WE LEADERS OF LEADERS جو کچھ کہیں گے وہی آخری اور قطعی فیصلہ ہو گا.یعنی ہم جو راہنماؤں کے راہنما ہیں اصل کام ہمارا ہے.اتنے زیادہ لیڈروں کا کام نہیں کہ اکٹھے ہو کر فیصلہ کر دیں.غرض میں نے دیکھا کہ ان پر یہ امر بڑا گراں گذرا کہ اتنی تعداد میں لوگوں کو کیوں لیڈر قرار دیا گیا.حالانکہ وہاں کسی ایک قوم کے لیڈر جمع نہیں تھے.بلکہ ہندوؤں، سکھوں اور مسلمانوں سب کے نمائندے تھے.جس طرح افراد کا دماغ بعض دفعہ اس رنگ میں بگڑ جاتا ہے.اسی طرح بعض دفعہ قوموں میں بڑائی شروع ہو جاتی ہے اور پھر ان کی تسلی نہیں ہوتی جب تک کہ تمام قوموں کو اپنے مقابلہ میں غلام اور اچھوتوں سے بھی بد تر قرار نہ دے دیں.ابھی چند دن ہوئے اخبارات میں بڑا شور اٹھا کہ پہلے تو اقبال جیسے لوگوں کو علامہ لکھا جاتا تھا.مگر اب یہ حالت ہے کہ ہر وہ آدمی جو اردو بھی صحیح پڑھ نہیں سکتا.اس کے نام کے ساتھ علامہ لکھ دیا جاتا ہے.چنانچہ لدھیانہ میں ایک جلسہ ہوا تو ہر مقرر کے نام کے ساتھ لکھا گیا کہ یہ فلاں علامہ تھے اور وہ فلاں علامہ تھے حالانکہ حالت یہ تھی کہ وہ صحیح طور پر اردو بھی نہیں جانتے تھے.اس قسم کی وبا کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ جو لوگ واقعہ میں علامہ ہوتے ہیں.ان کے لئے کوئی اور لفظ تجویز کیا جاتا ہے اور دوسروں کو ان کے مقابل میں گرانے کی کوشش کی جاتی ہے اور اس طرح نہ صرف منافرت کی ایک وسیع خلیج چھوٹوں اور بڑوں میں حائل ہو جاتی ہے.بلکہ ذہنیتیں اس قسم کی ہو جاتی ہیں کہ کچھ لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم بڑے ہیں اور باقی لوگ ہمارے غلام ہیں.ہم جب بچے تھے.تو میں نے اور میر محمد اسحٰق صاحب مرحوم نے حضرت خلیفۂ اوّل رضی اللہ عنہ سے پڑھنا شروع کیا.استاد کا یوں بھی دلوں میں زیادہ اعزاز ہوتا ہے.مگر حضرت خلیفۂ اوّل رضی اللہ عنہ کو تو جماعت میں بھی ایک خاص پوزیشن حاصل تھی اس وقت جب بھی یہ بات کہی جاتی کہ مولوی صاحب نے یہ کہا ہے تو اس سے مراد یا حضرت خلیفۂ اوّل رضی اللہ عنہ ہوا کرتے تھے یا حضرت مولوی عبدالکریم صاحب مراد ہوا کرتے تھے.جب بھی
Page 352
کسی نے کہنا مولوی صاحب نے یہ بات کہی ہے تو سننے والا کہتا کون مولوی صاحب.اور وہ کہتا حضرت خلیفہ اوّلؓ یا کہتا مولوی صاحب نے یہ بات کہی ہے.اور سننے والا کہتا کہ کون مولوی صاحب تو وہ کہتا مولوی عبدالکریم صاحب.چند دن تک تو میر محمد اسحق صاحب یہ سنتے رہے.مگر ایک دن ان کو بڑا غصہ آیا کہ یہ کیا بات ہے کہ یہ بھی مولوی صاحب اور وہ بھی مولوی صاحب.ان کا نام آئے تب بھی لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب نے یہ کہا اور ان کا نام آئے تب بھی لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب نے یہ کہا.یہ بالکل غلط طریق ہے.آئندہ مولوی عبدالکریم صاحب کی کوئی بات ہو گی تو میں کہوں گا مولوی صاحب نے یہ کہا ہے.اور خلیفۂ اوّلؓ کی کوئی بات ہو گی تو میں کہوں گا چولوی صاحب نے یہ کہا ہے.گویا انہوں نے امتیاز کا یہ نرالا طریق نکالا کہ ایک کو مولوی صاحب کہا جائے اور دوسرے کو چولوی صاحب کہا جائے یہ ہے تو بچپن کی ایک حماقت.لیکن واقعہ یہی ہے کہ جب کسی کو کوئی خاص اعزاز حاصل ہو جائے تو اس کے مقابل میں دوسروں کو کہا جاتا ہے کہ تم چھوٹے درجہ کے ہو.پھر ان کو اور چھوٹا کیا جاتا ہے.پھر اور چھوٹا کیا جاتا ہے.یہاں تک کہ ہوتے ہوتے وہ مکمل غلام بن جاتے ہیں.پس غلام کی آزادی درحقیقت قوم کی آزادی ہے.یہ دس یا بارہ آدمیوں کا سوال نہیں بلکہ قوم کا کیرکٹر تبھی بلند ہوتا ہے جب غلط اصول پر قائم شدہ امتیازات کو مٹا دیا جائے.اسی طرح خدا کی خوشنودی بھی اسی وقت حاصل ہوتی ہے جب غلاموں کو آزاد کیا جائے یا غلاموں کو آزاد کرانے کی سرگرم کوشش کی جائے.فَکُّ رَقَبَۃٍ کے دوسرے معنی غلط عقائد کی اصلاح اور رسم و رواج کی پابندیوں کو توڑ دینے کے بھی ہیں.اللہ تعالیٰ کفار کی نسبت فرماتا ہے اُولٰٓىِٕكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ١ۚ وَ اُولٰٓىِٕكَ الْاَغْلٰلُ فِيْۤ اَعْنَاقِهِمْ (الرّعد:۶) یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا کفر کیا اور جن کی گردنوں میں اغلال پڑے ہوئے ہیں.اس جگہ کفر و شرک کے معنوں میں اغلال کا لفظ استعمال ہوا ہے.اور بتایا گیا ہے کہ یہ وہ طوق ہیں جنہوں نے ان کی گردنوں کو خم کیا ہوا ہے.اسی طرح یہود کی نسبت فرماتا ہے.وَیَضَعُ عَنْہُمْ اِصْرَھُمْ وَالْاَغْلٰلَ الَّتِیْ کَانَتْ عَلَیْھِمْ (الاعراف:۱۵۸ ) ہمارا یہ رسول ان کے اِصر کو دور کرتا ہے اور ان کے اغلال کو کاٹتا ہے.ان ہر دو آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ فَکُّ رَقَبَۃٍ کے معنے جہاں غلام آزاد کرنے کے ہیں وہاں غلط عقائد رسم و رواج کی سختیاں، جھوٹے نظام جو ظالم سرداروں کو سَرپر بٹھا دیں.جیسے احبار وجابر بادشاہ جن کی وجہ سے قوم اپنی گردن اوپر نہ اٹھا سکے.وہ بھی اس میں شامل ہیں.پس فَکُّ رَقَبَۃٍ کے معنے یہ ہوئے کہ ہم تو ان کو غلامی سے آزاد کرانے لگے تھے.مگر ان کو اپنے اغلال توڑنے کی ہمت نہ پڑی.انہوں نے غلاموں کو آزاد کرنے کی کوشش نہیں کی.انہوں نے قوم کے ادنیٰ طبقہ کو ابھارنے کی کوشش نہیں
Page 353
کی.انہوں نے رسم و رواج کو چھوڑنے کی کوشش نہیں کی.انہوں نے جھوٹے عقائد کو ترک کرنے کی کوشش نہیں کی اور اس طرح وہ تباہی و بربادی کے گڑھے میں ہی گرے رہے.اَوْ اِطْعٰمٌ فِيْ يَوْمٍ ذِيْ مَسْغَبَةٍۙ۰۰۱۵ یا بھوک کے دن کھانا کھلانا ہے.حلّ لُغات.مَسْغَبَۃٍ.سَغَبَ الرَّجُلُ سَغْبًا وسُغُوْبًا وسَغَبًا وَسَغَابَۃً وَمَسْغَبَۃً (اقرب) کے معنے ہیں جَاعَ وہ بھوکا رہا (اقرب) پس مَسْغَبَۃٌ کے معنے بھوکے رہنے کے ہوئے.تفسیر.فرماتا ہے اگر اس کے اندر یتامیٰ و مساکین کی حقیقی محبت ہوتی اور وہ ان کی تکالیف کو دور کرنے کا صحیح احساس اپنے اندر رکھتا تو اس کا فرض تھا کہ وہ بھوک والے دن ان کو کھانا کھلاتا.یعنی قحط میں ان کی خبرگیری کرتا یا فقر وفاقہ میں ان کے لئے غلّہ وغیرہ مہیا کرتا.یہ مان لیا کہ وہ سو سو اونٹ ایک ایک دن میں ذبح کرتا رہا ہے.مگر ہم تو یہ کہتے ہیں وہ بے موقعہ ذبح کرتا رہا ہے اور ان کو ذبح کرنے کا موقع یہ تھا کہ وہ یتامیٰ ومساکین کے لئے ان کو ذبح کرتا اور ان کا گوشت ان میں تقسیم کر دیتا یا خود پکا کر ان کو دعوت دے کر ان کی بھوک کو دور کرتا.یہاں فِیْ یَوْمٍ ذِیْ مَسْغَبَۃٍ کے الفاظ اسی حکمت کے ماتحت لائے گئے ہیں کہ پہلے یہ ذکر آ چکا تھا کہ وہ نام ونمود کے لئے، جاہ طلبی اور شہرت کے حصول کے لئے اپنا روپیہ صرف کر دیتا ہے.اس سے خیال پیدا ہو سکتا تھا کہ ممکن ہے وہ یتامٰی ومساکین کو بھی کھلا دیتا ہو.اللہ تعالیٰ نے اس شبہ کا ازالہ کیا ہے اور بتایا ہے کہ وہ روپیہ تو خرچ کرتا تھا.اپنے اونٹوں کو بھی ذبح کرتا تھا مگر بھوک والے دن نہیں.یعنی جب بھوکوں کو ضرورت ہوتی تھی.وہ ان کو ذبح نہیں کرتا تھا.بلکہ جب اپنی شہرت کا جنون اس کے سر پر سوار ہو جاتا تو سو سو اونٹ ایک ایک دن میں ذبح کر دیتا.حالانکہ اگر حقیقی ضرورت کو مدنظر رکھ کر وہ کام کرتا تو دوستوں کی دعوت کے لئے صرف ایک اونٹ ذبح کرتا اور ننانوے اونٹ یتامیٰ و مساکین کے لئے رکھ لیتا.تاکہ ان کو فاقہ کی مصیبت پیش نہ آتی.پس چونکہ اس نے قومی ضرورت کو مدنظر نہیں رکھا اور اپنے مال کو بے موقعہ خرچ کر کے ضائع کر دیا.اس لئے ہماری نگاہ میں وہ کسی تعریف کا مستحق نہیں نہ اس قابل ہے کہ لوگ اس کو احترام کی نظر سے دیکھیں.
Page 354
يَّتِيْمًا ذَا مَقْرَبَةٍۙ۰۰۱۶ یتیم کو جو قریبی ہو.تفسیر.یتیم کےساتھ ذَا مَقْرَبَةٍ کے الفاظ لانے کی وجہ یہاں یتیم کے ساتھ ذَا مَقْرَبَۃٍ کے الفاظ کا اضافہ اس لئے کیا گیا ہے کہ قرابت والا یتیم بہرحال انسان کو اپنے پاس رکھنا پڑتا ہے اور اس کے خوردونوش کی ذمہ داری یا تعلیم اور لباس وغیرہ کے اخراجات انسان کو برداشت کرنے پڑتے ہیں.یہ الگ امر ہے کہ کوئی شخص ان اخراجات کو طوعًا برداشت کرے یا کرہاً مگر بہرحال خاندانی ذمہ داریاں تقاضا کرتی ہیں کہ انسان اپنے قرابت دار یتیم کا خیال رکھے.مگر فرمایا تمہاری تو یہ حالت ہے کہ تم ایسے یتیم کو بھی کھانا نہیں کھلاتے جو تمہارا قریبی رشتہ دار ہوتا ہے جو اس بات کا ثبوت ہے کہ تمہاری حالت خطرناک حد تک گر چکی ہے.اس آیت کے یہ معنے نہیں کہ قریبی یتیم کو تو کھانا کھلانا چاہیے.مگر دوسرے کو نہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ کسی اور یتیم کی پرورش تو الگ رہی.تم سے تو اس بات کی بھی امید نہیں کی جا سکتی کہ تم اپنے قریبی یتیموں کی خبرگیری کرو گے اور ان کی ضروریات کا خیال رکھو گے.جب ایک قریبی ذمہ داری سے تم اس قدر لاپروا ہو تو دور کی ذمہ داری کے پورا کرنے کی طرف تمہاری توجہ ہی کہاں ہو سکتی ہے.اَوْ مِسْكِيْنًا ذَا مَتْرَبَةٍؕ۰۰۱۷ یا مسکین کو جو زمین پر گرا ہوا ہو.تفسیر.مِسْکِیْنًا ذَامَتْرَبَۃٍ کے لفظی معنے تو یہ ہیں کہ وہ مسکین جو خاک افتادہ ہو مگر اس کے مفہوم دو ہیں.اوّل.ایسا غریب جو مالی لحاظ سے بالکل ادنیٰ اور ذلیل حالت میں ہو.ہماری زبان میں بھی کہتے ہیں.فلاں شخص تو مٹی میں مل گیا ہے.یعنی اس کی نہایت ہی قابل رحم حالت ہے.دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ ایسا مسکین جو مالی کمزوری کے ساتھ جسمانی طور پر بھی ایسا کمزور اور بیمار ہو کہ وہ چل پھر نہ سکتا ہو.گویا اس میں اتنی طاقت بھی نہیں رہتی کہ وہ امیروں کے دروازہ تک پہنچ کر سوال کر سکے.کمزوری اس قدر بڑھی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ زمین پر لیٹا ہوا ہوتا ہے اور کوئی اس کا پُر سان حال نہیں ہوتا.یا اتنا کمزور ہوجاتا ہے
Page 355
کہ مانگنے کی طاقت بھی نہیں رکھتا.جس شخص کے دل میں ایسے مساکین کے متعلق بھی رحم کا جذبہ پیدا نہ ہو جو بالکل کنگال ہو چکے ہوں یا ساتھ ایسے بیمار بھی ہوں کہ مانگنے کی سکت بھی نہ رکھتے ہوں.وہ خدا سے کیا فضل مانگ سکتا ہے اور بندے اس کی کیا عزت کر سکتے ہیں.اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مشکلات کے وقت ان لوگوں سے بھی کام کی امید کی جاتی ہے جو عام طور پر معذور سمجھے جاتے ہوں.مگر پھر بھی کچھ لوگ ایسے ضرور ہوتے ہیں.جن کا بوجھ انسان کو اٹھانا پڑتا ہے جیسے اپنے قریبی یتیم اور بالکل ناکارہ انسان جن سے کمائی کی کوئی امید نہیں کی جا سکتی.مگر یہ ان لوگوں کی پرورش سے بھی مصائب کے وقت غافل ہوتا ہے.حالانکہ مصائب کے وقت ہی انسانی اخلاق کا تجربہ ہوتا ہے.ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا پھر (چوٹی پر چڑھنا یہ تھا کہ ان کاموںکے علاوہ) یہ ان میں سے بن جاتا جو ایمان لائے.وَ تَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَ تَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِؕ۰۰۱۸ اور (جنہوں نے) ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی اور ایک دوسرے کو رحم کرنے کی نصیحت کی.تفسیر.ثُمَّ کَانَ مِنَ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا....الـخ کہہ کر بتایا ہے کہ خالی نیک اعمال کافی نہیں.بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ اس کے ساتھ ایمان بھی ہو اور قوم میں نیکی پیدا کرنے کا جذبہ بھی ہو.اس جگہ ایمان سے عام ایمان مراد نہیں.بلکہ ان اعمال خیر کے متعلق ایمان مراد ہے جن کا ذکر اوپر ہو چکا ہے اور مراد یہ ہے کہ ان اعمال پر کاربند ہونے کے علاوہ دل میں یہ یقین ہو کہ یہ اعمال ضروری ہیں منافقانہ رنگ میں ان پر عمل نہ کرتا ہو.کیونکہ منافقانہ عمل میں ایسا جوش کبھی پیدا نہیں ہوتا کہ کماحقہ ان کو بجا لاسکے.سچی بشاشت اسی عمل کے ساتھ پیدا ہوتی ہے جس کے ضروری اور درست ہونے پر انسان کو یقین بھی ہو.دوسرے معنے اس کے یہ ہیں کہ اگر خلوص سے یہ لوگ ان اعمال کو بجا لاتے تو انہیں تقویٰ نصیب ہوتا اور اس کے نتیجہ میں ان کو ایمان بھی نصیب ہو جاتا.گویا ثُمَّ کے معنے ’’اس کے ساتھ ہی‘‘ کے بھی ہو سکتے ہیں اور پھر کے بھی.اور یہ دونوں معنے لغت کے لحاظ سے ثابت ہیں.ساتھ ہی کے لحاظ سے یہ معنے ہوں گے کہ یہ نیک اعمال بھی کرتے اور ساتھ ہی مومن بھی ہوتے.یعنی بغیر اس عمل کے اچھا ہونے پر یقین ہو نے کے عمل کا مل نہیں ہوتا.منافقت جڑوں کو کھوکھلا کر دیتی ہے.اور اگر ثُمَّ کے معنے ’’اس کے بعد‘‘ کے کئے جائیں تو اس کے یہ معنے ہوں گے کہ یہ
Page 356
نیک اعمال کرتے اور ان کے بعد مومن بن جاتے.یعنی ان اعمال کا نتیجہ یقیناً یہ نکلتا.کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم پر ایمان بھی ان کو مل جاتا.کیونکہ نیک نیتی کے ساتھ کیا ہوا عمل ایمان کی طرف لے جاتا ہے.رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم سے حکیم بن حزام نے جو نبوت کے دعویٰ سے پہلے آپؐکے دوست تھے.آپؐسے پوچھا کہ کفر میں جو صدقہ وخیرات میں نے کیا تھا کیا وہ ضائع گیا؟ تو آپ نے فرمایا اَسْلَمْتَ عَلٰی مَا سَلَفَ مِنْ خَیْرٍ (الصحیح البخاری کتاب الادب باب من وصل فی الشـرک ثم اسلم) ضائع کیوں گیا.اسی عمل کے نتیجہ میں تو تم کو دولت اسلام حاصل ہوئی.پھر فرماتا ہے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَۃِ پہلے معنوں کے مطابق اس جملہ کے یہ معنے ہوں گے کہ اگر ان اعمال کے ساتھ ساتھ انہیں ان اعمال کی خوبیوں پر ایمان بھی نصیب ہوتا.اور یہ لوگ خود ہی وہ اعمال نہ بجا لاتے.بلکہ دوسروں کو بھی ان کے استقلال کے ساتھ بجا لانے کا حکم دیتے اور رحم کرنے کی تلقین کرتے رہتے تو ان کے لئے بابرکت ہوتا.تَوَاصَوْا کے معنے بار بار تاکید کرنے کے ہیں.اور صبر کے معنے اس جگہ استقلال سے کام کرنے کے ہیں.اور مَرْحَـمَۃ کے معنے رحم کے ہیں.دوسرے معنوں کے رو سے اس جملہ کے یہ معنے ہوں گے کہ ان نیک اعمال کے بعد انہیں ضرور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم پر ایمان لانے کی توفیق ملتی.اور نیکی کا جذبہ اتنا قوی ہو جاتا کہ اب تو یہ لوگ ظلم کرتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم پر ایمان لا کر یہ خود ظلم شو ق سے برداشت کرتے اور دوسروں کو ظلم کو صبر سے برداشت کرنے کی تلقین کرتے رہتے.باوجود ظلموں کو برداشت کرنے کے اپنے دشمنوں پر بھی رحم کرتے اور دوسرے دوستوں کو بھی نصیحت کرتے کہ دشمن کے ظلم پر غصہ میں نہ آؤ.بلکہ باوجود اس کے ظلم کے پھر بھی رحم سے کام لو.اُولٰٓىِٕكَ اَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِؕ۰۰۱۹ یہی لوگ تو برکت والے ہوں گے.تفسیر.اَصْحٰبُ الْمَیْمَنَۃِ کے دو معنے مَیْمَنَۃ کے معنے برکت کے بھی ہیں اور مَیْمَنَۃ کے معنے دائیں کے بھی ہوتے ہیں.(اقرب) قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن جن لوگوں کے دائیں ہاتھ میں نامۂ اعمال دیا جائے گا وہ عزت پائیں گے اور جنت کے حقدار ہوں گے.اس مناسبت سے اَصْـحَابُ الْمَیْمَنَۃ کے دونوں معنے ہو سکتے ہیں.یہ بھی کہ وہ لوگ جن میں اوپر کی باتیں پائی جائیں اور وہ احکامِ الٰہی
Page 357
پر عمل کریں.وہ قیامت کے دن ان لوگوں میں شامل ہوں گے جن کے دائیں ہاتھ میں نامۂ اعمال دیا جائے گا.اور یہ بھی معنے ہوسکتے ہیں کہ ایسے لوگ ہی اللہ تعالیٰ کی برکات کو حاصل کرتے ہیں.جو احکامِ الٰہیہ کی متابعت کو خوشی سے قبول کرتے ہیں.وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا هُمْ اَصْحٰبُ الْمَشْـَٔمَةِؕ۰۰۲۰ اور جنہوں نے ہماری آیتوں کا کفر کیا وہ نحوست والے ہوں گے.حلّ لُغات.مَشْئَمَۃٌ.مَشْئَمَۃٌ کے معنی بائیں کے بھی ہوتے ہیں.اور مَشْئَمَۃٌ نحوست کو بھی کہتے ہیں.(اقرب) تفسیر.پہلی آیت کی طرح اس آیت کا بھی ایک تو یہ مفہوم ہے کہ جو لوگ احکامِ الٰہیہ کا انکار کریں گے وہ قیامت کے دن ان لوگوں کی صف میں کھڑے کئے جائیں گے جن کے بائیں ہاتھ میں نامۂ اعمال دیا جائے گا.اور ایک معنے یہ ہیں کہ ایسے لوگ اپنے نفس اور اپنی قوم کے لئے سخت منحوس ہیں.ناکامی ان کے شامل حال رہے گی.عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤْصَدَةٌؒ۰۰۲۱ ان پر بھٹی کی آگ (کی سزا) نازل ہو گی.حلّ لُغات.اَلْمُؤْصَدَۃ.اَلْمُؤْصَدُ کے معنے ہیں.اَلْمُطْبَقُ وَالْمُغْلَقُ بند کی ہوئی چیز (اقرب) پس نَارٌ مُّؤْصَدَةٌ کے معنے ہوں گے ایسی آگ جو بند کی گئی ہو.تفسیر.پہلے لوگ شائد نَارٌ مُّؤْصَدَةٌ کی حقیقت کو پوری طرح نہ سمجھتے ہوں مگر موجودہ زمانہ کے لوگوں کے لئے اس کی حقیقت کو سمجھنا کچھ بھی مشکل نہیں کیونکہ نئے علوم نے واضح کر دیا ہے کہ سخت ترین آگ وہ ہوتی ہے جس پر چاروں طرف سے دروازے بند کر دئیے جائیں.بھٹی کی آگ اسی لئے تیز ہوتی ہے کہ اسے چاروںطرف سے بند کر کے صرف ایک چھوٹا سا سوراخ رکھ لیا جاتا ہے جو آگ اس طرح بھڑکائی جائے وہ اس قدر تیز ہوتی ہے کہ سب کچھ جلا کر بھسم کر دیتی ہے.اللہ تعالیٰ اس آیت میں کفار کے انجام کا ذکر کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ آج تو یہ لوگ اسلام کے مقابل میں
Page 358
کھڑے ہیں اور مسلمانوں کو سخت سے سخت اذیتیں پہنچانے کے درپے ہیں.مگر وہ یاد رکھیں ایک دن وہ ایسی آگ میں ڈالے جائیں گے جو چاروں طرف سے بند ہو گی.اور جو انہیں جلا کر راکھ کر دے گی.یعنی اسلام اور مسلمانوں کے مقابلہ میں کفار مکہ ایسے تباہ ہوں گے کہ ان کا نشان تک باقی نہیں رہے گا.چنانچہ دیکھ لو وہ کیسے تباہ ہوئے کہ لات اور منات اور عُزّیٰ کی پرستش کرنے والا آج ساری دنیا میں کوئی ایک وجود بھی نظر نہیں آتا.خدا نے ان کو اپنے عذاب کی چکّی میں اس طرح پیسا اور اپنے غضب کا ان کو ایسا نشانہ بنایا کہ دنیا میں ان کا کچھ بھی باقی نہیں رہا.