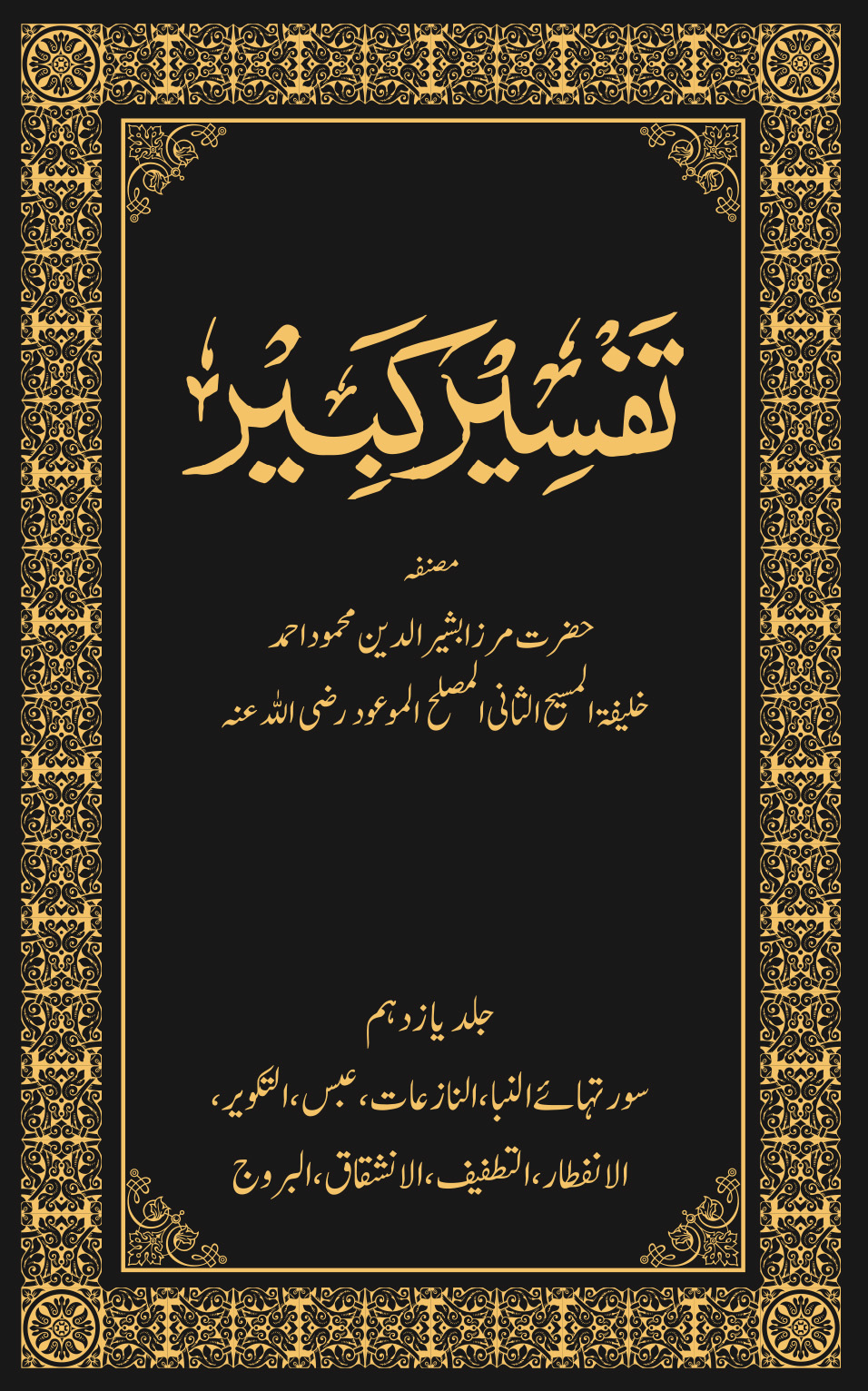Complete Text of Tafseer-e-Kabeer Volume 11
Content sourced fromAlislam.org
Page 5
سُورَۃُ النَّبَاِ مَکِّیَّۃٌ سورۃ نبا.یہ سورۃ مکی ہے وَھِیَ اَرْبَعُوْنَ اٰیَۃً دُوْنَ الْبَسْمَلَۃِ وَ فِیْھَا رُکُوْعَانِ اور بسم اللہ کے علاوہ اس کی چالیس آیتیں ہیں اور دو رکوع ہیں سورۃ النبا کی وجہ تسمیہ یہ سورۃ النَّبَا کہلاتی ہے کیونکہ اس میں اصل ذکر ایک نبأ عظیم کا ہے.اس سورۃ میں بعث بعد الموت، قرآن کریم یا غلبۂ اسلام کا ذکر ہے یا یوں کہو کہ ان تینوں کا ذکر ہے.اس سورۃ کا پہلی سورۃ سے تعلق یہ ہے کہ پہلی سورۃ میں یومِ فصل کی طرف خصوصیت سے توجہ دلائی گئی ہے چنانچہ سورۃ الْمُرْسَلٰتکے پہلے رکوع میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِاَيِّ يَوْمٍ اُجِّلَتْ.لِيَوْمِ الْفَصْلِ.وَ مَاۤ اَدْرٰىكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ(المرسلت:۱۳ تا ۱۵) یعنے کس دن کے لئے وعدہ دئیے گئے ہیں فیصلے کے دن کے واسطے اور تُوکیا جانے کہ و ہ فیصلے کا دن کیا ہے.اسی طرح فرماتا ہے ھٰذَا یَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَاکُمْ وَالْاَوَّلِیْنَ (المرسلت:۳۹)یعنے یہ فیصلے کا دن ہے کہ جس کے لئے ہم نے تم کواور تم سے پہلے لوگوں کو جمع کیا ہے.گویا ایک یومِ فصل کا اس جگہ پر ذکر تھا.اس سورۃ میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ یَوْمَ الْفَصْلِ کَانَ مِیْقَاتًا.یعنی یقیناً یہ فیصلے کا دن ایک مقرر وقت پر آنےوالا ہے.تو گویا سورۃ الْمُرْسَلَاتاور سورۃ النَّبا دونوں کا باہمی تعلق یومِ فصل کے ذریعہ سے ہے پہلی سورۃ میں دو دفعہ یومِ فصل کا بیان ہے اور اس سورۃ میں ایک دفعہ یومِ فصل کے ذکر کو دہرایا گیا ہے یہ بتانے کے لئے کہ ان دونوں میں اشتراکِ مضمون پایا جاتا ہے.اُس سورۃ میں بھی یومِ فصل کا بیان تھا اور اِ س سورۃ میں بھی یومِ فصل کا بیان ہے.سورۃ نباء کا پہلی سورۃ سے تعلق سورۃ النَّباابتدائی مکّی سورتوں میں سے ہے(فتح البیان سورۃ النبا ابتدائیہ).اس کی ترتیب کے متعلق نولڈک NOLDEKEجو مشرقی علوم کے متعلق جرمنی کامشہور پروفیسر ہے لکھتا ہے کہ اس سورۃ کے مضمون سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ سورۃ الْمُرْسَلَات کے ساتھ ہی اُتری ہے(تفسیر القرآن از وہیری تعارف سورۃ النباء) یہ ردّ ہے اُن مستشرقین یورپ کا جو کہا کرتے ہیںکہ قرآن کریم کی سورتوںمیں کوئی خاص ترتیب نہیں.لمبی سورتیں پہلے رکھ دی گئی ہیں اور چھوٹی سورتیں آخر میں رکھ دی گئی ہیں(THE KORAN by J.M Rodwell pg.2 preface ).اِن لوگوں کی سمجھ میں بھی جہاں جہاں کوئی بات آجاتی ہے وہاں انہیں تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ سورتوں کا مضمون آپس میں ملتا ہے.اور گو وہ سارے قرآن کو ایک باترتیب کلام نہ مانیں مگر کسی کسی جگہ انہیں بھی یہ
Page 6
تسلیم کئے بغیر چارہ نہیں رہتا کہ سورتوں کا جوڑ ایک دوسری سے ملتا ہے.بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۰۰۱ (میں) اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا بار بار رحم کرنے والا ہے (پڑھتا ہوں) عَمَّ يَتَسَآءَلُوْنَ۠ۚ۰۰۲ یہ (لوگ) کس (چیز) کے بارے میں ایک دوسرے سے (بطریق انکار) سوال کر رہے ہیں حل لغات.عَمَّاصل میںعَنْ مَا ہے نونؔ چونکہ میمؔ میں مدغم ہو جاتا ہے اس لئے عَمَّا ہو گیا.عربی زبان کا یہ محاورہ ہے کہ حروف جارہ کے بعد بالعموم مَااستفہامیہ کے الف کو حذف کر دیتے ہیںاور آخر مِیم پر فتحہ بطور علامت کے رکھ دیتے ہیں (اقرب زیر حرف ’’م‘‘) مثلاً کہتے ہیں.فِیْمَ.لِمَ.بِمَا.اِلَامَ.عَلٰی مَ.عَمَّ.بلکہ عام قاعدہ یہ ہے کہ وزن کے لحاظ سے جہاں الف ظاہر کرنے کا فائدہ ہو وہاں الف لاتے ہیں ورنہ بالعموم اس کو حذف کر دیتے ہیں.یعنی جہاں توازن میں یا بولنے میں زیادہ سہولت الف کے لانے میں ہو اُسی جگہ الف ظاہر کرتے ہیں ورنہ نہیں.یَتَسَآءَلُوْنَ اَلتَّسَاءُ لُ کے معنے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے پوچھنا.اور جب تَسَأَلَ الْقَوْمُ کہیں تو معنے ہوں گے سَأَ لَ بَعْضُھُمْ بَعْضًا (اقرب ) یعنی آپس میں ایک دوسرے سے انہوں نے پوچھا.اور یَتَسَآءَ لُوْنَ کے معنے ہوں گے آپس میں وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں.پس عَمَّ یَتَسَآءَ لُوْنَکے معنے ہوں گے آپس میں ایک دوسرے سے وہ کس کے بارے میں پوچھتے ہیں یا کس کے بارے میں وہ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں.تفسیر.سوال کی مختلف اغراض ایک دوسرے سے سوال مختلف وجوہ کی بنا پر کئے جاتے ہیں.کبھی سوال زیادتی ٔ علم کے لئے ہواکرتا ہے یعنی ایک انسان دوسرے انسان سے علم حاصل کرنا چاہتا ہے.مثلاً کسی کو راستہ معلوم نہیں تو وہ دوسرے سے پوچھتا ہے فلاں رستہ کدھر کو جاتا ہے یا پوچھتا ہے فلاں شہر کی طرف کون سا رستہ جاتا ہے.یا کسی لفظ کے معنے معلوم نہ ہوں تو وہ دوسرے سے پوچھتا ہے فلاں لفظ کے کیا معنے ہیں.اور یا پھر سوال امتحان کے لئے ہوا کرتا ہے یعنی سوال کرنے والا جانتا تو ہے کہ جس لفظ کے متعلق وہ پوچھ رہا ہے اس کے کیا معنے ہیں
Page 7
مگر وہ یہ معلوم کرنا چاہتا ہے کہ آیا دوسرے کو بھی وہ معنے معلوم ہیں یا نہیں.یہ سوال بھی بلاواسطہ عدمِ علم پر ہی دلالت کرتا ہے کیونکہ گو اس کو ان معنوں کا علم تو ہوتا ہے مگر اُسے یہ علم نہیں ہوتا کہ دوسرے کو بھی اس کا علم ہے یا نہیں.لیکن کبھی سوال اظہارِ تعجب کے لئے بھی ہوا کرتا ہے جیسے بعض دفعہ بیٹا اپنے باپ کی گستاخی کرے تو باپ اُسے کہتا ہے تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ یعنی تمہیں اتنی سمجھ تو ہونی چاہیے کہ میں تمھارا باپ ہوں اور باپ کا ادب کرناضروری ہوتا ہے یا آقا اپنے غلام کو یا افسر اپنے ماتحت کو کہتا ہے تم جانتے ہو مَیں کون ہوں؟ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اُسے علم نہیں ہوتا کہ وہ کون ہے.پھر اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہوتا کہ تم نہیں جانتے ہو کہ میں کون ہوں.بلکہ اس موقع پر سوال کرنے والا یہ بھی جانتا ہے کہ وہ کون ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ جس سے سوال کیا گیا ہے وہ بھی جانتا ہے کہ حقیقت کیا ہے.مگر باوجود اس کے کہ جس سے سوال کیا جاتا ہے وہ بھی جانتا ہے اور باوجود اس کے کہ جو سوال کرنے والا ہے وہ یہ بھی جانتا ہے کہ میرا مخاطب اس سوال کا جواب جانتا ہے پھر بھی وہ سوال کرتا ہے.تو درحقیقت یہ سوال ایک قسم کے تعجب کے اظہار کے لئے ہوتا ہے اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم کو پتہ ہے کہ حقیقت کیا ہے پھر باوجود علم ہونے کے تم کیوں غفلت کر رہے ہو یا باوجود پتہ ہونے کے تم پوچھ کیوں رہے ہو یا اختلاف کیوں کر رہے ہو.اور کبھی اسی تعجب کی صورت میں تفخیم کے لئے یعنی اس چیز کی عظمت کے اظہار کے لئے بھی سوال کیا جاتا ہے.عَمَّ يَتَسَآءَلُوْنَ۠ کے فقرہ میں سوال کی وجہ یہاں بھی درحقیقت مخفی معنے تعجب کے ہی ہیںگو یہاں تفخیم کا پہلو بھی نمایاں ہے.جیسے میں نے ابھی ایک مثال دی ہے کہ بعض دفعہ سوال کرتے ہوئے کہا جاتا ہے تم جانتے ہو میں کون ہوں اور اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ میری جو کچھ شان اور عظمت ہے اُس سے تم بخوبی واقف ہو.قرآن کریم چونکہ خدا کا کلام ہے اس لئے یہاں نہ تو یہ معنے ہو سکتے ہیں کہ خدا نہیں جانتا.نہ دوسرے معنے ہو سکتے ہیں کہ خدا کو یہ شک ہے کہ میرا مخاطب جانتا ہے یا نہیں جانتا پس تیسرے ہی معنے ہیں جو خدا کے متعلق چسپاں ہو سکتے ہیں اور وہی معنی اس جگہ پر لئے جائیں گے جیسا کہ اگلی آیت نے اس کو ظاہر بھی کر دیا ہے.پس عَمَّ يَتَسَآءَلُوْنَ۠کے یہ معنے ہیں کہ ہمیں تعجب ہے کہ بغیر کافی غور اور فکر کے یہ لوگ ایک ایسے امر کے متعلق سوال کرتے ہیں جس کے حقائق ظاہر ہیں.گویا ایک طرف تو اس سوال میں مسئلہ کی بڑائی پر زور ہے اور بتایا گیا ہے کہ وہ مسئلہ بہت ہی اہم ہے اور اس کے حقائق بالکل ظاہر ہیںاور دوسری طر ف وہ لوگ جن کے متعلق یہ فقرہ کہا گیا ہے اُن کی عقل پر اظہار تعجب کیا گیا ہے کہ باجود اس مسئلہ کے دلائل موجو دہونے کے پھر بھی وہ شبہات میں پڑے ہوئے ہیں.
Page 8
عَنِ النَّبَاِ الْعَظِيْمِۙ۰۰۳ اس (مذکورہ بالا یَوْمُ الْفَصْل ۱؎ والی) عظیم (الشان) خبر کے متعلق (سوال کر رہے ہیں) حل لغات.نَبَأٌ کے معنے خبر کے ہوتے ہیں لیکن علّامہ ابوالبقاء اپنی کتاب کلیات میں لکھتے ہیں کہ اَلنَّبَأُ وَالْاِنْبَائُ لَمْ یَرِدَافِیْ الْقُراٰنِ اِلَّا لِمَا لَہٗ وَقْعٌ وَشَاْنٌ عَظِیْمٌ (بحوالہ اقرب)یعنی نَبأ اوراِنْبَاء کے الفاظ قرآن کریم میں کسی جگہ بھی سوائے ایسے امر کے جس کی بہت بڑی شان اور اہمیت ہو استعمال نہیں ہوتے.وَقْعٌ تاثیر اور اہمیت کو کہتے ہیں.امام راغب اپنی کتاب مفردات میں لکھتے ہیں اَلنَّبَأُ خَبَرٌذُوْفَائِدَۃٍ عَظِیْمَۃٍ یَحْصُلُ بِہٖ عِلْمٌ اَوْ غَلَبَۃُ ظَنٍّ وَّلَایُقَالُ لِلْخَبَرِ فِیْ الْاَصْلِ نَبَأٌ حَتّٰی یَتَضَمَّنَ ھٰذِہِ الْاَشْیَائَ الثَّلٰثَۃَ یعنی نبأ اس خبر کو کہتے ہیں جس میں اوّل فائد ہ ہو.دوسرے بڑا فائد ہ ہو.تیسرے اُس کے ذریعہ سے یا تو علم یقین حاصل ہوتا ہو یا علم غیب حاصل ہوتا ہو.پھر وہ کہتے ہیں خبر کو کبھی اس کے حقیقی معنوں میں نبأ نہیں کہتے جب تک یہ تینوں باتیں اُس میں نہ پائی جاتی ہوں.گویا اس طرح انہوں نے مزید زور اس بات پر دیا کہ نبأ کے یہ تین معنے ہیں اور جب تک یہ تینوں معنے کسی خبر میں نہ پائے جائیں ہم اسے نبأ نہیں کہہ سکتے سوائے اس کے کہ کوئی سرسری طور پر اس لفظ کا استعمال کر دے یا غلط طور پر استعمال کردے.مگرچونکہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں کسی لفظ کا غلط استعمال نہیں ہو سکتا اس لئے ابوالبقاء نے کہا ہےکہ قرآن کریم میں ان معنوں کے سوا کہیں بھی نبأ کا لفظ استعمال نہیں ہوا.جب بھی قرآن کریم میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے انہی معنوں میں استعمال ہوتا ہے.وَقْعٌ وَشَاْنٌ عَظِیْمٌ کے الفاظ بھی درحقیقت یہی تینوں معنے ظاہر کرتے ہیں کیونکہ وَقْعٌ کے معنے وہی ہیں جو امام راغب نے خَبَرٌذُوْفَائِدَۃٍ کے الفاظ میں بیان کئے ہیں.اور عظیمٌ کا لفظ فَائِدَۃ عَظِیْمَۃ کی طرف اشارہ کرتا ہے اور شَاْنٌ کے معنے وہی ہیں جو یَحْصُلُ بِہٖ عِلْمٌ اَوْ غَلَبَۃُ ظَنٍّ کے ہیںکیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کُلَّ یَوْمٍ ھُوَ فِیْ شَاْنٍ (الرحمٰن :۳۰ )پس وَقْعٌ وَشَاْنٌ عَظِیْمٌ کے الفاظ میں درحقیقت وہی مضمون پایا جاتا ہے جو مفردات والے نے بیان کیا.مفردات والے نے بتا دیاکہ نبأ کا لفظ جب بھی صحیح طور پر استعمال کیا جائے گا اُس میں یہ تین باتیں ضرور پائی جائیں گی اور ابوالبقاء نے کہہ دیا کہ اَلنَّبَأُ وَالْاِنْبَائُ لَمْ یَرِدَافِیْ الْقُراٰنِ اِلَّا لِمَا لَہٗ وَقْعٌ وَشَاْنٌ عَظِیْمٌ قرآن کریم میںنبأ اور انباء کا لفظ کہیں ۱؎ اس یوم الفصل سے مراد وہ یوم الفصل ہے جس کا ذکر سورۃ النبا سے پہلی سورۃ المرسلات میں آچکا ہے.
Page 9
بھی استعمال نہیں ہوا مگر اسی صورت میںجب اُس خبر کی بہت بڑی شان اور اہمیت ہو.مطلب یہ ہے کہ قرآن چونکہ الفاظ کا صحیح استعمال کرتا ہے.اس لئے جب بھی قرآن کریم میں یہ لفظ استعمال ہوگاان تینوں معنوں پر مشتمل ہوگا.اسی بنا پر میں غیر مبایعین کے مقابلہ میں کہا کرتا ہوں کہ تم جو کہتے ہوکہ ہر وہ شخص جس پر الہام الٰہی نازل ہو اسے لغوی طور پر ہم نبی کہہ سکتے ہیں یہ بالکل غلط ہے.نبی کے لغوی معنی لغوی طور پر نبوت کے معنوں میں صرف الہام کے نزول کا مفہوم نہیں پایا جاتا.بلکہ لغت کے لحاظ سے نبی وہ ہوتا ہے جس پر خدا تعالیٰ کا کلام نازل ہوتا ہو اور اُس کلام میں یہ تین شرطیں پائی جاتی ہوں.اوّل وہ ذُوْفَائِدَۃٍ ہو دوم ؔوہ ذُوْفَائِدَۃٍ عَظِیْمَۃٍ ہو.سومؔوہ ایسا الہام ہویَحْصُلُ بِہٖ عِلْمٌ اَوْ غَلَبَۃُ ظَنٍّ اور پھر زائد بات بوجہ نبی کے صیغہ کے یہ پائی جائے گی کہ اُس پر کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کلام نازل ہوتاہو.گویانبأ کو جب ہم نبی کے صیغہ میں تبدیل کر دیں تو اس کے معنے ہوں گے ایسا شخص جس پر کثرت سے کلام الٰہی نازل ہوتا ہے اور پھر وہ کلام ایسا ہوتا ہے جو ذُوْفَائِدَۃٍ عَظیْمَۃٍ یَحْصُلُ بِہٖ عِلْمٌ اَوْ غَلَبَۃُ ظَنٍّ کا مصداق ہوتا ہے.گویا نبی وہ ہے جو اللہ کی طرف سے کثرت کے ساتھ لوگوں کو خبر یں دیتا ہے اور ایسی خبریں دیتا ہے جو فائدہ پر مشتمل ہوتی ہیں اور نہ صر ف فائدہ پر بلکہ فائدہ عظیمہ پر مشتمل ہوتی ہیںاور یَحْصُلُ بِہٖ عِلْمٌ اُن سے زائد علم حاصل ہوتا ہے پس جب ہم کسی کو نبی اللہ کہتے ہیں تو اس کے معنے یہ ہوتے ہیں کہ نبی اللہ وہ ہے (۱)جو اللہ تعالیٰ کی طرف سےسن کر لوگوں کو کثرت سے خبریں دیتا ہے (۲) ایسی خبریں دیتا ہے جن میں فائد ہ ہوتا ہے اور فائد ہ بھی عظیم الشان ہوتا ہے اور (۳) پھر اُن سے علم زائد حاصل ہوتا ہے.ان معنوں کے رُو سے کسی صورت میں بھی غیر مبایعین یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ اس پہلو میں اُمت محمدؐیہ کا کوئی اور فرد بھی شریک ہے اور نہ درحقیقت وہ یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ ان معنوں کے رُو سے کوئی غیر نبی کسی نبی کا شریک ہو سکتا ہے.کیونکہ یہ باتیں کسی غیر نبی میں پائی ہی نہیں جاتیں.تفسیر.عَنِ النَّبَاِ الْعَظِيْمِکا تعلق پہلی آیت سے عَنِ النَّبَاِ الْعَظِیْمِ جملہ مستانفہ بھی ہو سکتا ہے اور عَنْ عَمَّ کا بدل بھی ہو سکتا ہے.یعنی یہ بھی اس کے معنے ہو سکتے ہیںکہ کس بارے میںسوال کر رہے ہیں.کیا اس عظیم الشان نبأ کے متعلق جس کا آگےذکر ہوگا اور یا پھر یہ جملہ مستانفہ ہے اور مطلب یہ ہے کہ پہلی آیت میں تو یہ کہا گیا تھا کہ کس بارے میں یہ لوگ آپس میں سوال کر رہے ہیں.اب اس کا خود ہی جواب دیتا ہے کہ عَنِ النَّبَاِ الْعَظِیْمِ یہ لوگ سوال کر رہے ہیں ایک عظیم الشان نبأکے متعلق.اس دوسری آیت نے بتا دیا کہ عَمَّ يَتَسَآءَلُوْنَ۠
Page 10
میں جو عمَّہ تھا وہ سوال جہالت کی وجہ سے نہیں تھا یا عدم علم کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ عَمَّ يَتَسَآءَلُوْنَ۠ کہنے والی ہستی جانتی تھی کہ وہ کس چیز کے بارے میں آپس میں بحث کر رہے ہیں کیونکہ وہ خود بتاتی ہے کہ اُن کاآپس میں تَسَآءُ ل نبأ عظیم کے متعلق تھا.اس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ایک زائد بات بیان فرمائی ہے جو نہایت غور کے قابل ہے اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہےعَمَّ يَتَسَآءَلُوْنَ۠ عَنِ النَّبَاِ الْعَظِیْمِ یہ لوگ کس کے بارے میں سوال کر رہے ہیں آیا ایک عظیم الشان نبأ کے متعلق یا جملہ مستانفہ کی صورت میں اس کے یہ معنے ہوں گے کہ یہ لوگ سوال کر رہے ہیںایک عظیم الشان نبأ کے متعلق.جیسا کہ لغت سے ظاہر ہے نَبَأ کے معنے یہ ہوتے ہیں کہ اَلنَّبَأُ خَبَرٌ ذُوْفَائِدَۃٍ عَظِیْمَۃٍ اوربقول کلیات کے نبأ وہ ہے مَالَہٗ وَقْعٌ وَشَاْنٌ عَظِیْمٌ گویا عَظِیْمٌ کا لفظ خود نبأ میں شامل ہے.مگر یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عَنِ النَّبَاِ الْعَظِیْمِ.یعنی نَبَأ کی حیثیت اور شان والی جو خبریں ہیں اُن میں سے بھی یہ عظیم الشان خبر ہے گویا بڑیوں میں سے بڑی اورعظیموں میں سے عظیم ہے.جب نَبَأ خود اپنے اندر ایک عظمت اور شان رکھتی ہے تو اُس کے ساتھ عظیم کے لفظ کا لا یا جانا بتاتا ہے کہ اس کے معنے یہی ہیںکہ بڑیوں میں سے بڑی، عظیموں میں سے عظیم اور شانداروں میں سے شاندار خبر.اب نَبَأ کے اصل معنوں کو مدنظر رکھتے ہوئے اگر ہم اس آیت کا تفسیری طور پر ترجمہ کریں تو وہ یوں ہو گاکہ کیا یہ لوگ سوال کرتے ہیں اُس خبر کے متعلق جو شاندار خبروں میں سے بھی بڑی شاندار خبر ہے.النَّبَاِ الْعَظِيْمِسے مراد تین امور اس جگہ نَبَأ سے مراد بعض نے قرآن کریم لیا ہے اور بعض نے بعث بعد الموت چنانچہ ابن کثیر میں ہے کہ قتادہ اور ابن زید کہتے ہیں اَلنَّبَأُ الْعَظِیْمُ:اَلْبَعْثُ بَعْدَ الْمَوْتِ کہ نَبَأ عظیم سے مرادمرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا ہے.پھر ابن کثیر میں ہی لکھا ہے کہ مجاہد کہتے ہیں ھُوَالْقُرْاَنُ یعنی نبأ عظیم سے مراد قرآن ہے(تفسیر ابن کثیر زیر آیت ھذاٰ ) لیکن اس سے پہلی سورۃ یعنی سورۃ المرسلات میں صرف قرآن کا ہی ذکر نہیں بلکہ قرآن کے غلبہ کا بھی ذکر کیا گیا ہے چنانچہ قرآن کا تو سورۃ المرسلات کی اس آخری آیت میں ذکر ہے کہفَبِاَيِّ حَدِيْثٍۭ بَعْدَهٗ يُؤْمِنُوْنَ (المرسلت:۵۱).اور غلبۂ قرآن کا اس آیت میں ذکر ہے کہ كُلُوْا وَ تَمَتَّعُوْا قَلِيْلًا اِنَّكُمْ مُّجْرِمُوْنَ.وَيْلٌ يَّوْمَىِٕذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ(المرسلت:۴۷،۴۸)اور پھر یوم الفصل کا جو ذکر کیا گیا ہے اُس میں بھی غلبہ ٔ اسلام کی پیشگوئی ہے پس صرف قرآن کا ہی نہیں بلکہ غلبۂ اسلام کا بھی اس سورۃ میں ذکر ہے اور یہ دونوں ذکر اس سورۃ نبأ سے بھی ظاہر ہیںاور اس سے پہلی سورۃ سے بھی.نبأ عظیم سے تین امور مراد لئے جانے کے متعلق ایک شبہ کا ازالہ اس موقع پر یہ شبہ دل میں
Page 11
پیدا نہیں ہونا چاہیے کہ ان تین چیزوں میںسے کون سی چیز یہاں مراد ہے کیونکہ قرآن کریم کے کئی بطن ہوتے ہیں اور قرآن کریم بعض دفعہ ایک ہی دلیل سے کئی کئی مضمون ثابت کرتا ہے.مثلاًاگر کسی جگہ یہ ذکر ہوکہ زید فلاں ملک میں گیا ہے یا نہیں اور دوسری جماعت میں یہ بحث ہو کہ زید ایک مغلوب شخص تھا یا غالب.تو اگر ہم یہ فقرہ کہہ دیں کہ زید اس ملک میں گیا اور اُس نے فتح پائی.تو یہ فقرہ ان دونوں سوالوں کو حل کر دے گا.اس فقرہ میں اس پارٹی کا بھی جواب آجائے گا جویہ بحث کرتی تھی کہ زید اس ملک میں گیا تھا یا نہیں اور اُس پارٹی کا بھی جواب آجائے گاجو یہ بحث کرتی تھی کہ زید مغلوب شخص تھا یا غالب.اسی طرح بعض دلائل کا مجموعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ صرف ایک نتیجہ پیدا نہیں کرتا بلکہ کئی نتائج اُس سے پیدا ہو جاتے ہیں.پس جب ہم کوئی دلیل بیان کریں تو جتنے پہلو اس دلیل میں سے نکل سکتے ہوں وہ سارے ہی ثابت ہو جائیں گے.بعث بعد الموت اور احیاءِ روحانی کا آپس میں لازم و ملزوم ہونا بعث بعد الموت درحقیقت اُس بعثِ روحانی کے مشابہ چیز ہے جو اس دنیا میں ہوتی ہے.اس لئے ایک دلیل دوسری دلیل کو ثابت کر دیتی ہے.بعثِ روحانی اس بات کا ثبوت ہوتی ہے کہ بعث بعد الموت بھی ہو گی اور بعث بعد الموت اس بات کا ثبوت ہے کہ بعثِ روحانی بھی ضرور ہوتی ہے.اگر اللہ تعالیٰ انسان کی روح کو مدارجِ عالیہ پر پہنچاتا ہے تو ایسی روح کا کوئی عظیم الشان مقصد اور مدعا ہونا چاہیے.ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مدارجِ عالیہ پر پہنچا کر اللہ تعالیٰ روح کو فنا کر دے گا اور آگے اس کا کوئی کام نہیں ہو گا.اور اگرمرنے کے بعد انسان کے لئے کوئی زندگی ہے توپھر لازماً اس دُنیا میں احیاءِ روح بھی ہونا چاہیے کیونکہ ایک انسان کو دائمی چکر میں ڈال دینا اور اس ابدی زندگی میں جو خلودوالی ہے اللہ تعالیٰ کے انعامات حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ نہ بتانا یہ بھی ایک ظلم ہے.اگر اللہ تعالیٰ ہم کو مرنے کے بعد خلود والی زندگی بخشے گاتو لازماًاس زندگی سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اُٹھانے کا سامان بھی اس دُنیا میں ہونا چاہیے.گویا ان دونوں سوالوں کا انحصار ایک دوسرے پر ہے اگر ایک ہے تو لازماً دوسری بھی ہے اور اگر دوسری ہے تو لازماً پہلی بھی ہے.اور چونکہ وہ روحانی زندگی جو اس دنیا میں حاصل ہوتی ہے اُس کے متعلق قرآن کریم یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس زمانہ میں روحانی زندگی بخشنے والا میں ہی ہوں اس لئے یہ بھی پہلے دونوں سوالوں کے ساتھ شریک ہو گیا.یعنی جس دلیل سے یہ ثابت ہو گا کہ اس دنیا میں احیا ءِ روح کے کوئی سامان ہونے چاہئیں وہ قرآن کریم کے دعویٰ کے مطابق یہ بھی ثابت کرے گی کہ قرآن کریم سچا ہے کیونکہ قرآن کریم ہی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس زمانہ میں روحانی زندگی بخشنے کے لئے وہ مقرر ہے.پس ایک ہی دلیل سے یہ تینوں امر ثابت ہو جائیں گے.اگر کسی دلیل سے یہ ثابت ہو گا کہ مرنے کے بعد کی زندگی ایک یقینی چیز ہے اور
Page 12
وہ ضرور آنےوالی ہے تو اُسی دلیل سے یہ بھی ثابت ہو جائے گا کہ اس دنیا میں احیائِ روح کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سامان رکھے گئے ہیں اور پھر ساتھ ہی یہ بھی ثابت ہو جائے گا کہ قرآن کریم کا یہ دعویٰ کہ میں ہی اس کام کوسر انجام دیتا ہوں بالکل صحیح اور درست ہے.کیونکہ اگر یہ ثابت ہو جائے گا کہ روحانی مدارج جو نہایت اعلیٰ درجہ کے ہیں انسان کو اس دنیا میں ملتے ہیں تو ساتھ ہی یہ ثابت ہو جائے گا کہ قرآن کریم ہی یہ درجے دینے والا ہے.اس لئے کہ یہ درجے قرآن کریم کو ماننے والوں کوہی حاصل ہوتے ہیں اَور لوگوں کو حاصل نہیں ہوتے.اسی طرح جب یہ ثابت ہو جائے گاکہ قرآن کریم پر عمل کرنے کے نتیجہ میں بڑے سے بڑے روحانی مدارج انسان کو اس دنیا میں حاصل ہو سکتے ہیں تو ساتھ ہی یہ بھی ثابت ہو جائے گاکہ مرنے کے بعد بھی زندگی ہے کیونکہ ان مدارجِ روحانیہ کے حصول کو ہم لغو اور فضول نہیں کہہ سکتے.گویا اگر یہ ثابت ہو گا کہ قرآن کریم روحانی مدارج عطا کرتا ہے تواس کے لازماً یہ معنے ہوں گے کہ قرآن کریم پر عمل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑے بڑے مدارج عطا ہوں گے.اور اگر یہ ثابت ہو گا کہ قرآن کریم پر عمل کرنے کے نتیجہ میںانسان کو روحانی مدارج حاصل ہوتے ہیں تو ساتھ ہی یہ بھی ثابت ہو جائے گاکہ مرنے کے بعد ضرور کوئی زندگی ہے کیونکہ یہ ممکن نہیں کہ انسان کو اعلیٰ قابلیتیں دے کر اُن کے ظہور کا موقع ملنے سے پہلے اُسے فنا کر دیا جائے.پس یہ تینوں چیزیں آپس میں لازم ملزوم ہیں اور ان میں سے ایک کے ثابت ہونے سے باقی دو چیزیں خود بخود ثابت ہو جاتی ہیں.غرض اگر ہم نبأ عظیم کے معنے قرآن کریم کے لیں اور پھر ساتھ ہی بعث بعد الموت اور غلبۂ اسلام کے بھی تو یہ کوئی شبہ والی بات نہیں ہو گی بلکہ تینوں معنے آپس میں لازم ملزوم ہوں گے.بعض چیزوں کاتعددشک پر دلالت کرتا ہے اور بعض چیزوں کا تعدد لزوم پر دلالت کرتا ہے.یہاں تعددِ لزومی ہے تعددِ شکی نہیں.نبأ عظیم کا لفظ جو اس موقع پر استعمال ہوا ہے وہ درحقیقت ان تین معنوں پر ہی استعمال ہو سکتا ہے کیونکہ مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے وہ بھی ایک ایسی خبر ہے جو بڑی خبروں کی سرتاج ہے.یہ کہہ دینا کہ فلاں کے ہاں بیٹا پیدا ہو جائے گایا فلاں ملک میں لڑائی ہو جائے گی اس خبر کے مقابلہ میں بہت ہی ادنیٰ اور معمولی ہیں.بے شک یہ خبریں بھی اپنی ذات میں بڑی اہمیت رکھتی ہیں مگر یہ خبریں اُس قدر اہمیت نہیں رکھتیں جتنا یہ کہنا کہ ایک زمانہ میں ساری دنیا زندہ کی جائے گی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو گی.پسنبأ عظیم کا لفظ قیامت کے بالکل مطابق ہے اور یہ لفظ اُس پر بخوبی چسپاں ہو جاتا ہے.اسی طرح نبأ عظیم کا لفظ قرآن کریم پر بھی چسپاں ہو جاتا ہے اس لئے کہ قرآن کریم یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں ساری خوبیوں کا جامع ہوں بلکہ گز شتہ تما م انبیاء کی کتابیں میرے اندر جمع ہیں جیسا کہ وہ فرماتا ہےفِیْھَا کُتُبٌ قَیِّمَۃٌ (البیّنۃ:۴)
Page 13
پس اگر نوح ؑکے صحف نَبَأ تھے.اگر ابراھیم ؑکے صحف نَبَأ تھے.اگرموسیٰ ؑ کے صحف نبأ تھا.اسی طرح اگر عیسیٰ ؑ کاکلام نَبَأ تھا.اگر کریشن ؑکا کلام نَبَأ تھا اگر رام چندرؑ کا کلامنَبَأ تھا.اگر زرتشتؑ کا کلام نَبَأ تھاتو جس کلام میں یہ سارے ہی جمع کر لئے گئے ہوں وہ یقیناً نَبَأ عظیم کہلائے گا.اس طرح غلبہ ٔ اسلام بھی ایک ایسی چیز ہے جو تمام انبیاء کے غلبوں میں سے عظیم الشان رنگ رکھتی ہے اور درحقیقت یہ غلبہ ایسا ہے جس نے تمام انبیاء کے غلبو ں کو اپنے اندر جمع کر لیا ہے.مثلاً حضرت نوح علیہ السلام کا طوفان لے لو.نوح ؑکی قوم نے غرق ہو کر نوح ؑ کی صداقت کا ثبوت دیا اور نوح ؑ اپنی قوم پر غالب آ گیا.مگر اس کا کیا نتیجہ ہوا یہی کہ قوم غرق ہو گئی اور وہ نوح پر ایمان لانے سے محروم رہی.لیکن محمد رسول اللہ صلے اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کی قوم اس طرح غرق کی گئی کہ وہ پھر آپ پر ایمان بھی لے آئی.موسیٰ ؑ کو اپنے دشمنوں پر اس طرح غلبہ دیا گیا کہ موسیٰ ؑ کا دشمن سمندر میں ڈبو دیا گیا مگر محمد صلے اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کا دشمن سمندر کی بجائے خشکی میں ڈبو دیا گیا اور پھر خدا نے یہ سامان کئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جس ملک کا وعدہ دیا گیا تھا اُس ملک پر غلبہ دئیے جانے کا وعدہ ان کی زندگی میں پورا نہ ہوا.اس کے مقابلہ میں رسول کریم صلے اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح غلبہ کا وعدہ دیا گیا مگر انہوں نے اپنی زندگی میں ہی مکّہ کو فتح کر لیا.حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا تعالیٰ نے اس طرح غلبہ دیا کہ وہ اپنے دشمن سے بھاگے اور ایک غیر ملک میں اُس کے حملہ سے محفوظ ہو گئے.رسول کریم صلے اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس رنگ میں غلبہ دیا کہ آپ دشمن سے بھاگے اور ایک دوسرے شہر میں جا کر اُس کے حملہ سے محفوظ ہو گئے.لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر اپنے ملک میں واپس نہیں آئے اور نہ انہوں نے اپنی قوم کو مغلوب کیا مگر رسول کریم صلے اللہ علیہ وآلہٖ وسلم پھر مکّہ میں واپس آئے اور انہوں نے اپنی قوم کو مغلوب کرلیا.غرض جس جس رنگ میں پہلے انبیاء کو غلبہ ملااُن میں سے ہر رنگ میں رسول کریم صلے اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کو غلبہ حاصل ہوا اور نہ صر ف غلبہ حاصل ہوا بلکہ اُن سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی نصرت اور اُس کی تائید آپؐ کے شامل حال رہی.مثلاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو تین سو سال میں غلبہ حاصل ہوامگر رسول کریم صلے اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کو اپنی زندگی میں ہی غلبہ مل گیا.اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السّلام کو ایسے ساتھی ملے جنہوں نے قربانی کے موقع پر کمزوری دکھائی اور وہ ثابت قدم ثابت نہ ہوئے.لیکن رسول کریم صلے اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ ساتھی عطا فرمائے جنہوں نے نہ موسیٰ ؑ کے ساتھیوں جیسی کمزوری دکھائی اور نہ عیسیٰ ؑکے ساتھیوں جیسی کمزوری دکھائی.موسیٰ ؑ کے ساتھیوں نے جنگ کے موقع پرکمزوری دکھائی تھی اور عیسیٰ ؑ کے ساتھیوں نے اُس وقت کمزوری دکھائی جب ان کی اپنی جان خطرے میں تھی.
Page 14
غلبہ اسلام کے مختلف نظارے درحقیقت دنیا میں دو قسم کے جذبات لوگوں کے اندر پائے جاتے ہیں.بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قوم کی خاطر قربانی کرنے کے لئے تو تیار رہتے ہیں لیکن اپنے لیڈر کے لئے قربانی کرنے پرآمادہ نہیں ہوتے.اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو اپنے لیڈر کی خاطر تو ہر وقت قربانی کرنےکے لئے تیار رہتے ہیں لیکن اپنی قوم کے لئے قربانی کرنےکی روح اُن میں موجود نہیں ہوتی.اُنہیں صرف عشق ذاتی ہوتا ہے عشق قومی نہیں ہوتا.مگر رسول کریم صلے اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ ساتھی عطا فرمائے جو یہ دونوں جذبات اپنے دلوں میں رکھتے تھے جہا ں قوم کے لئے انہیں قربانی کرنی پڑی وہاں آپ کے صحابہ ؓنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں جیسا نمونہ نہ دکھایا بلکہ اپنی قوم کے لئے ہر قسم کی قربانی کرنے کے لئے تیار ہو گئے اور جہاں رسول کریم صلے اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کی ذات کا سوال پیدا ہوا وہاں انہوں نے اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کر اُس عشق کا ثبوت دیا جو اُن کو رسول کریم صلے اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کی ذات کے ساتھ تھا اور حضرت مسیح ؑ کے حواریوں کی طرح بزدلی نہیں دکھائی.چنانچہ مکہ کے لوگ جب رسول کریم صلے اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کو قتل کرنے کے ارادہ سے ایک دفعہ رات کو آپؐ کے مکان کے اردگر د اکٹھے ہو گئے اور رسول کریم صلے اللہ علیہ وآلہٖ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہجرت کے ارادہ سے گھر سے نکل پڑے تو اُس وقت آ پ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر لٹا دیا(السیرۃ النبویۃ لابن ہشام زیر عنوان خروج النبی واستخلافہ علیا علی فراشہ).اور اس طرح حضرت علی ؓ نے اس امر کا ثبوت دے دیا کہ رسول کریم صلے اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کے صحابہ آپ کی جگہ خود صلیب پر لٹکنے کو تیار رہتے تھے تو عشق ذاتی میں بھی رسول کریم صلے اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کی قوم دوسرے نبیوں کی قوموں سے بڑھ گئی اور عشقِ قومی میں بھی رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم کی قوم دوسرے نبیوں کی قوموں سے بڑھ گئی.اس لئے آپ کا جو غلبہ تھا یعنی غلبۂ اسلام وہ بھی نبأ عظیم تھا کیونکہ یہ غلبہ پہلے انبیاء کے غلبوں کے مقابلہ میں نہایت ہی شاندار تھا اور آپ کی جو کتاب تھی وہ بھی نبأ عظیم تھی کیونکہ وہ گزشتہ تمام الہامی کتابوں سے بہت زیادہ شاندار تھی.اور قیامت بھی نبأ عظیم ہے کیونکہ وہ اور تمام خبروں سے بہت زیادہ شان اور عظمت اپنے اندر رکھتی ہے.
Page 15
الَّذِيْ هُمْ فِيْهِ مُخْتَلِفُوْنَؕ۰۰۴ جس کے بارے میں یہ لوگ (قرآن کی بتائی ہوئی حقیقت سے ) اختلاف رکھتے ہیں.حل لغات.مُخْتَلِفُوْنَ مُخْتَلِفُوْنَ مُخْتَلِفٌ کی جمع ہے اور مُختَلِفٌ اِخْتَلَفَ سے اسم فاعل کا صیغہ ہے جس کے معنےآپس میں ایک دوسرے سے اختلاف کرنے کے ہیں (اقرب) پس مُخْتَلِفُوْنَ کے معنے ہوں گے اختلاف کرنے والے.اور اَلَّذِیْ ھُمْ فِیْہِ مُخْتَلِفُوْن کے معنے ہوں گے جس میں وہ اختلاف ظاہرکررہے ہیں.تفسیر.یہاں تفخیم اورا ستعجاب کا پہلو زیادہ نمایاں ہے کیوں کہ پہلے ایک خبر کو نبأ عظیم قرار دیتا ہے.اور پھر فرماتا ہے اَلَّذِیْ فِیْہِ مُخْتَلِفُوْنَ یعنی وہ نبأ عظیم جس میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں گویا اول تو نبأ میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے تھا اور پھرنبأ عظیم میں تو کسی صورت میں بھی اختلاف نہیں ہو سکتا تھا مگر یہ وہ لوگ ہیں جو نبأ عظیم میں بھی اختلاف کر رہے ہیں.گویا ادھر ایک ایسی عظیم الشان خبر موجود ہے اور اُدھر یہ لوگ ایسے ذلیل ہیں کہ اس عظیم الشان خبر میں بھی اختلاف کرتے ہیں.بعث بعد الموت قرآن اور غلبہ اسلام کے متعلق کفار کا اختلاف اور اس کا مطلب بعض لوگوں نے اس موقع پر اعتراض کیا ہے کہ الَّذِيْ هُمْ فِيْهِ مُخْتَلِفُوْنَ کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ اس جگہ نبأ عظیم سے مراد قرآن نہیں اور نہ بعث بعد الموت مراد ہے.کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کفّار ان امور میں اختلاف کرتے تھے حالانکہ وہ بعث بعد الموت کے منکر تھے اور وہ تسلیم ہی نہیں کرتے تھے کہ مرنے کے بعد بھی کوئی زندگی ہے.پس جب وہ اس عقید ہ کو تسلیم ہی نہیں کرتے تھے تو اس میں وہ اختلاف کیونکر کرسکتے تھے.اسی طرح قرآن کریم پر بھی وہ ایمان نہیں رکھتے تھے پس قرآن کریم کے متعلق بھی یہ نہیں کہا جاسکتا کہ کفّار اس کے متعلق اختلاف کیاکرتے تھے.لیکن یہ اعتراض درست نہیں.اس لئے کہ سب کے سب کفّار بعث بعد الموت کے منکر نہیں تھے بلکہ اُن میں بھی اس بارہ میں اختلاف تھا گو وہ اس بعث کی شکل اَور سمجھتے ہوں.گویا اوّل تو سب کفّار اس عقیدہ کے منکرنہیں تھے اور پھر جو لوگ اسکے قائل تھے اُن میں سے بعض کو صر ف بعث کی شکل میں اختلا ف تھا اسی وجہ سے عربوں میںیہ روایات پائی جاتی تھیں کہ جب کوئی شخص مارا جاتا ہے اور پھر اس مقتول کا بدلہ نہیں لیا جاتا تو اُس کی رُوح اُلُّو کی شکل میں آکر چیختی چلّاتی ہے(لسان العرب زیر مادہ ھوم).اگر وہ مرنے کے بعد کسی حیات کے قائل نہیں تھے تو اُلُّو کی شکل میں مقتول کی روح کے آنے کے وہ کس طرح قائل ہو سکتے تھے.پس درحقیقت وہ کسی حقیقی علم پر قائم نہیں تھے بلکہ خود اِ س بارہ میں اُن
Page 16
میں اختلاف موجود تھا کوئی کچھ کہتا تھااور کوئی کچھ کہتا تھا.قرآن کریم کی صورت میں بھی یہ سوال پید ا ہوتا ہے کہ الَّذِيْ هُمْ فِيْهِ مُخْتَلِفُوْنَ اس پر کس طرح چسپاں ہو سکتا ہے اور وہ اس بارہ میں کیا اختلاف کیا کرتے تھے وہ تو قرآن کریم کی صداقت کے قائل ہی نہیں تھے بلکہ کہتے تھے کہ یہ محض جھوٹ ہے اس میں سچائی کا کوئی شائبہ بھی نہیں پایا جاتا.مگر میرے نزدیک یہ سوال بھی درست نہیں اس لئے کہ قرآن کریم کے متعلق بھی ان کو اختلاف تھا.بعض اس کا نام سحر رکھتے تھے.بعض اُسے کذب قرار دیتے تھے (المدثر:۲۵) اور بعض اس کا نام اَسَا طِیْرُ الْاَوَّلِیْنَ (الانفال :۳۲) رکھتے تھے یہ سیدھی بات ہے کہ اَسَا طِیْرُ الْاَوَّلِیْنَ کہنے والوں کے نزدیک قرآن کریم جھوٹا نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ اگر قرآن کریم اُن کے نزدیک جھوٹا ہوتا توا س کے معنے یہ بنتے ہیں کہ وہ اپنے باپ دادا کوبھی جھوٹا قرار دیا کرتے تھے حالانکہ یہ صحیح نہیں.پس ان کاقرآن کریم کو اَسَا طِیْرُ الْاَوَّلِیْنَ قرار دیناہی بتا رہا ہے کہ اُن میں سے بعض کو قرآن کریم کے متعلق یہ اعتراض نہیں تھا کہ یہ کلام جھوٹا ہے بلکہ ان کا اعتراض یہ تھا کہ اس میں اُن کے باپ دادا کی باتوں کو ہی نقل کر دیا گیا ہے اس لئے ہم اس کو بطور خدا کی کلام کے نہیں مان سکتے.پس عربوں میں قرآن کریم کو اَسَا طِیْرُ الْاَوَّلِیْنَ کہنے والے بھی موجود تھے جو اس بات کا ثبوت ہے کہ انہیں قرآن کریم کے متعلق اختلاف تھا.اسی طرح قرآن کریم کو سحر کہنے والے بھی اُن میں موجود تھےاور قرآن کریم کو جھوٹا قرار دینے والے بھی ان میں موجود تھے.پس قرآن کریم کی صورت میں بھی یہ آیت پوری طرح چسپاں ہو جاتی ہے کہ الَّذِيْ هُمْ فِيْهِ مُخْتَلِفُوْنَ یعنی وہ نبأ عظیم ہے جس میں کفّار اختلاف کرتے ہیں.تیسر ا پہلو غلبۂ اسلام کا ہے ممکن ہے کوئی شخص کہہ دے کہ اس کے متعلق ان کو کہا ں اختلاف تھا تو اس کے متعلق بھی یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ غلبۂ اسلام کے متعلق بھی کفار میں اختلاف موجود تھاکفّار جانتے تھے کہ مسلمانوں کے اندر ایک ایسی روح کام کررہی ہے جو ایک دن اُن کو ہم پر غالب کر دے گی.چنانچہ اُن کا اسلام کی شدید ترین مخالفت کرنااور اس کی ترقی کو روکنے کے لئے اپنی انتہائی کوشش صرف کرنا خود اس بات کا ایک ثبوت ہے کہ وہ ڈرتے تھے کہ اسلام اُن پر غالب آجائے گااور وہ جانتے تھے کہ مسلمانوں کے اندر ایسی چیز موجود ہے جو اُن کے مقابلہ میں ہم کو مغلوب کردے گی.اور یہی سچے نبی کی علامت ہوا کرتی ہے کہ مخالفوں کے دلوں میں پہلے سے یہ ڈر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ ایک دن یہ لوگ ہم کو کھا جائیں گے اور ہماری طاقت کو توڑ کر رکھ دیں گے.وہ ایک طرف یہ بھی کہتے جاتے ہیں کہ ہم ان کو مار دیںگے.ہم ان کو تباہ کردیں گے.ہم ان کو دنیا سے مٹا دیں گے.مگر ساتھ ہی ان کے دلوں میںیہ خطرہ بھی موجود ہوتا ہے کہ یہ شخص ہم کو کھا جائے گایہی وجہ ہے کہ نبیوں کی دنیا میں شدید مخالفت ہوتی
Page 17
ہے ورنہ سب جانتے ہیں کہ وہ اکیلے ہوتے ہیں نہ اُن کے پاس جتھہ ہوتا ہے نہ اُن کے پاس طاقت ہوتی ہے نہ اُن کے پاس مال ہوتا ہے نہ اُن کے پاس ظاہر ی شان وشوکت کا کوئی اور سامان ہوتا ہے.وہ اکیلے اُٹھتے اور بے سروسامانی کی حالت میں دنیا کے مقابلے میں کھڑے ہو تے ہیں مگر پھر ساری دنیا اُن کی مخالفت کرنے لگ جاتی ہے اور وہ پورا زور اس بات پر صرف کر دیتی ہے کہ اُن کو کچل دے اُن کے نام کو مٹا دے اور ان کو اپنے مشن میں کامیاب نہ ہونے دے کیونکہ ان کے دلوں میں یہ خیال موجود ہوتا ہے کہ یہ شخص گو اکیلا ہے مگر اس میں ایسی ترقی کی قابلیت پائی جاتی ہے اور ایسی رُوح اس کے اندر نظر آتی ہے جو ایک دن ہم کو کھا جائے گی اور ہمیں اس کے مقابلہ میں پسپا کر دے گی.ہمارے اس زمانہ میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بعد بھی کئی لوگوں نے دعوے کئے مگر لوگ اُن کی طرف ذرا بھی توجہ نہیں کرتے جس پر وہ چڑتے ہیں کہ ہماری مخالفت کیوں نہیں کی جاتی.بلکہ بعض اُن میں سے ہمیںگالیاں دیتے ہیں کہ ہم اُن کی باتوںکا جواب کیوں نہیں دیتے.مگر باوجود اس کے کہ اُن کی خواہش ہوتی ہے کہ لوگ اُن کی مخالفت کریں.اُن کی باتوں کی طرف توجہ کریں پھر بھی کوئی شخص اُن کی طرف توجہ نہیں کرتا.اسی لئے کہ اُن میں وہ کوئی ایسی چیز نہیں دیکھتے جس سے اُن کے دلوں میں ڈر محسوس ہواوروہ یہ خیال کرنے لگ جائیں کہ یہ ایک دن ہم پر غالب آجائیں گے.لوگ اُن کی باتوں کو سنتے ہیں تو ہنس کر گذر جاتے ہیں کوئی مخالفت نہیں کرتے یا معتدبہ مخالفت نہیں کرتے.اتفاقیہ طور پر اُن کے متعلق منہ سے کچھ نکل جائے تو اور بات ہے ورنہ یُوں سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ آپ ہی تباہ ہو جائیں گے ہمیں ان کی مخالفت کرنے کی ضرورت نہیں.توالَّذِيْ هُمْ فِيْهِ مُخْتَلِفُوْنَ میں غلبہ اسلام کے معنوں کی طرف بھی اشارہ ہے اور بتایا گیا ہے کہ ان کفّار میںسے جو سمجھدار لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ چیز ایک دن غالب آنےوالی ہے.عوام الناس بے شک اپنے علماء کی باتیں سُن کر کہتے ہیں کہ یہ لوگ ہمارے مقابلہ میں فنا ہو جائیں گے مگر اُن کے علماء جانتے ہیں کہ آخر اسلام ہی جیتے گا اور وُہی ا س میدان میں شکست کھائیں گے بلکہ اُنہیں اپنی شکست کے ابھی سے آثار نظرآنے شروع ہو گئے ہیں.گویا پہلے دن سے ہی اسلام کی برتری اور اُس کے غلبہ کا اقرار ان لوگوں کو تھااور وہ سمجھتے تھے کہ اس مذہب کے مقابلہ میں ہم ٹھہر نہیں سکیں گے.اس زمانہ میں بھی ہم دیکھتے ہیں جماعت احمدیہ کی برتری کا احساس لوگوں کے قلوب میں موجود ہے اور وہ ڈرتے ہیں کہ اگر جماعت احمدیہ اسی طرح بڑھتی چلی گئی تو معلوم نہیں کہ کیا ہو جائے گا.اس لئے وہ مخالفت میں اپنا پورا زور صرف کر دیتے ہیں اور اس شدید مخالفت کی وجہ سے کسی کسی وقت یہ بھی سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ لوگ تباہ ہو جائیں گے.وہ خیال کرتے ہیں کہ اتنی مخالفتوں کے بعد بھلا یہ کہاں پنپ سکیں گے.پس هُمْ فِيْهِ مُخْتَلِفُوْنَ کے اس صورت میں یہ معنے
Page 18
نہیں ہوں گے کہ وہ آپس میں اختلاف رکھتے ہیں بلکہ جب ہم غلبہ ٔ اسلام کے معنے لیں گے تو اس آیت کا مفہوم یہ ہوگا کہ ان لوگوںکی حالتیں مختلف وقتوں میں مختلف ہوتی ہیں گویا اس صورت میں اختلاف یا تو عوام الناس اور اُن کے علماء میں سمجھا جائے گا اور یا پھر علماء کا آپس میں اختلاف اس سے مراد لیا جائے گا یعنی یا تو اس کا یہ مفہوم ہو گاکہ اس بارہ میں عوام الناس اور ان کے علماء اور لیڈروں میں اختلاف ہے عوام الناس یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان تباہ ہو جائیں گے مگر علماء اور لیڈر یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان تباہ نہیں ہو سکتے اور یا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بارہ میں علماء کی حالتیں بدلتی رہتی ہیں ایک حالت پر وہ قائم نہیں رہتے.کبھی وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کو مار لیں گے اور کبھی یہ خیال کرنے لگ جاتے ہیں کہ ہم ان کو کہاںمار سکتے ہیں ہم خود ہی ان کے مقابلہ میں پِس جائیں گے جب وہ مسلمانوں کی اندرونی خوبیوں اور اُن کی اعلیٰ درجہ کی صفات پر نگاہ دوڑاتے ہیں تو سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ ان مسلمانوں کے مقابلہ میں ہم مارے جائیں گے اور جب وہ اپنے جتھوں اور اپنی قوتوں پر نگاہ دوڑاتے ہیں تو سمجھتے ہیں ہم مسلمانوں کو مار لیں گے.هُمْ فِيْهِ مُخْتَلِفُوْنَ کی دوسری تشریح اسی طرح هُمْ فِيْهِ مُخْتَلِفُوْنَ کے ایک معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ مومن اور کافر آپس میں اختلاف رکھتے ہیں اور مومنوں اور کافروں کا یہ اختلاف بھی تین چیزوں کے متعلق سمجھا جائے گا.بعث بعد الموت کے متعلق غلبۂ قرآن کے متعلق اور غلبہ ٔ اسلام کے متعلق یعنی بعث بعد الموت کے متعلق مومن کچھ کہتے ہیں اورکافر کچھ کہتے ہیں.اسی طرح قرآن کے متعلق مومن کچھ کہتے ہیں اور کافر کچھ کہتے ہیں اور غلبۂ اسلام کے متعلق بھی مومنوں کا کچھ قول ہے اور کافروں کا کچھ قول ہے.كَلَّا سَيَعْلَمُوْنَۙ۰۰۵ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُوْنَ۰۰۶ (خوب یادر کھو کہ بات )یوں نہیں (جس طرح یہ کہتے ہیںبلکہ) یہ لوگ (قرآن کریم کی بتائی ہوئی حقیقت کو)عنقریب جان لیں گے.پھر (ہم کہتے ہیں کہ بات) یوں نہیں (جس طرح یہ کہتے ہیں بلکہ)یہ لوگ (قرآن کریم کی بتائی ہوئی حقیقت کو)عنقریب جان لیں گے.حل لغات.کَلَّا کَلَّا حرف ہے جو بات غلط ہو اُس سے ہوشیار کرنے کے لئے تنبیہ کے طور پر اس کا استعمال کیا جاتا ہے.یعنی یوں بات نہیں جس طرح کہ لوگ سمجھتے ہیں.علّا مہ ابو البقاء اپنی کتاب کلیات میں لکھتے ہیں
Page 19
قَدْ تَجِیْ ئُ بَعْدَالطَّلَبِ لِنَفْیِ اِجَابَۃِ الطَّالِبِ کَقَوْ لِکَ لِمَنْ قَالَ لَکَ اِفْعَلْ کَذَا.کَلَّا.اَیْ لَا یُجَابُ اِلٰی ذَالِکَ یعنی لفظ کَلَّا کسی مطالبہ کے جواب میں آتا ہے یہ بتانے کے لئے کہ مطالبہ کرنے والے کی بات ماننے کے لئے ہم تیار نہیں.چنانچہ جب ہمیں کوئی کسی امر کےکرنے کے لئے کہےاور ہم سمجھیں کہ یہ بات ایسی نہیں کہ کوئی مان سکے تو ہم کہیں گے کَلَّا پھر علّامہ ابوالبقاء لکھتے ہیںوَقَدْ جَاءَ بِمَعْنیَ حَقًّا.یعنی کبھی لفظ کَلَّا، حَقًّا کے معنے میں آتا ہے یعنی اس کے بعد بیان کی جانے والی بات کی تاکید کرتا ہے کہ یہ بات درست ہے جیسے قرآن مجید میں ہے کَلَّا اِنَّ الْاِنْسَانَ لَیَطْغٰی یعنی یہ بات درست ہے کہ انسان سرکشی کرتا ہے.(اقرب ) سَیَعْلَمُوْنَ وہ ضرور جان لیں گے.سؔ توکید کے معنوں میں یہاں آیا ہے ثُمَّ کَلَّا سَیَعْلَمُوْنَ یہاں ثُمَّ کا لفظ تکرار مضمون کے لئےاستعمال ہوا ہے یعنی پھر ہم کہتے ہیں کہ وہ بات اُس طرح ہر گز نہیں جس طرح وہ خیال کرتے ہیں.تفسیر.سَیَعْلَمُوْنَ وہ ضرور جان لیں گے یعنی قیامت کے دن ان کے یہ خیالات بالکل غلط ثابت ہوں گے اور اُن پر واضح ہو جائے گا کہ وہ کیسی کھلی غلطی میں مبتلا رہے.یا قرآن کریم مراد لیتے ہوئے اس کا یہ مطلب ہو گا کہ ایک دن آئے گا جب قرآن کریم کی صداقت اُن پر کُھل جائے گی.اور غلبۂ اسلام پر جب ان آیات کو چسپاں کیا جائے گاتو مفہوم یہ ہو گا کہ آخر اسلام ایک دن غالب آجائے گااور وہ سمجھ لیں گے کہ اسلام کی مخالفت کر کے انہوں نے کیسا غلط طریق اختیار کیا تھا.اب اگلی آیتو ںمیں اللہ تعالیٰ اپنے اس دعوےٰ کی دلیل دیتا ہے اور وہ دلیل ایسی ہے جو مذکورہ بالا تینوں معنوں پر چسپاں ہو سکتی ہے.یعنی اس دلیل سے نہ صرف قیامت کا وجود ثابت ہوتا ہے بلکہ غلبۂ قرآن اور غلبۂ اسلام کا بھی اسی سے ثبوت مل جاتا ہے.(اس آیت اوراگلی آیات کی تفسیر یکجائی طور پرآیت نمبر۸ یعنی وَّ خَلَقْنٰكُمْ اَزْوَاجًا کی آیت کے نیچے دی گئی ہے کیونکہ ان آیات کا مضمون اکٹھا ہے) اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ مِهٰدًاۙ۰۰۷ (سوچیں تو سہی کہ) کیاہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا.حل لغات.اِلْمِھَادُ: الْمِھَادُ اَلْفِرَاشُ وَالْاَرْضُ(اقرب ) یعنی مِھَاد کا لفظ فراش کے معنوں میں
Page 20
بھی استعمال ہوتا ہے اور زمین کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے.زمین کوجو مِھَاد کہتے ہیں اس کا بھی درحقیقت یہی مفہوم ہے کہ اُس میں فراش والی خوبیاں پائی جاتی ہیں.تفسیر.اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ مِهٰدًا کے معنے یہ ہیں کہ کیا ہم نے زمین کو ایسا نہیں بنایا جیسے فراش ہواکرتا ہے.فراش پر انسان کیا کرتا ہے.یہی کہ لیٹتا ہے آرام کرتا ہے.سوتا ہے اور اس طرح اُسے راحت حاصل ہوتی ہے.فرماتا ہے ہم نے زمین کو تمھارے لئے ایسا ہی بنایا ہے کہ تم اس میں ہر قسم کے آرام پاتے ہو.ہر قسم کی سہولتیں اس سے حاصل کرتے ہو اور تمھاری راحت کے تمام سامان اس میں موجود ہیں.فرماتا ہے تم زمین کی اس حالت پر غور کرو اور سوچو کہ کیا واقع میں ہم نے زمین کو تمھارے لئے ایسا بنایا ہے یا نہیںبنایا.وَّ الْجِبَالَ اَوْتَادًا۪ۙ۰۰۸ اور پہاڑوںکو میخوں کے طور پر.حلِّ لغات.اَوْ تَادٌ اَوْتَادٌ وَ تَدٌ کی جمع ہے اور وَتَدٌ کے معنے اُس چیز کے ہوتے ہیں جسے زمین یا مکان کی دیوار میں گاڑا جائے.گویا یہ لفظ کِیل کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے.لغت میں بھی پہاڑوں کو اَوْتَادُ الْاَرْضِ کہتے ہیں چنانچہ لکھا ہے اَوْ تَادُ الْاَرْضِ جِبَالُھَاوَاَوْ تَادُ الْبِلَادِ رُءُ ؤ سَاءُ ھَا وَاَوْ تادُ الْفَمِ اَسْنَانُہٗ (اقرب ) یعنی جب اَوْتَادُ الْاَرْضِ کہا جائے تو اس سے مراد پہاڑ ہوں گے جب اَوْ تَادُ الْبِلَادِ کہا جائے تو اس سے مراد مختلف ممالک کے رؤسا ہوں گے اور جب اَوْ تَادُالْفَمِ کہا جائے یعنی منہ کے اوتاد.تو اس سے مراد دانت ہوں گے کیونکہ جس طرح رؤساسے ملکی نظام قائم ہوتا ہے اسی طرح دانتوں سے منہ کا نظام قائم ہے.دانتوں سے انسان کھانا کھاتا ہے اور دانتوں سے ہی چہرے کا حُسن قائم ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ دانتوں کو اَوْ تَادُ الْفَمِ قرار دیا جاتا ہے.اسی طرح پہاڑوں سے چونکہ زمین میں حسن پیدا ہوتا ہے اور اس کی مضبوطی اور پختگی کا بھی وہ باعث ہوتے ہیں اس لئے پہاڑوں کو اَوْتَادُالْاَرْضِ کہا جاتا ہے.کِیل کی بھی یہی غرض ہوتی ہے کہ وہ ایک طرف مضبوطی کا باعث ہوتا ہے اور دوسری طرف بعض چیزوں کے لئے سہارے کا موجب ہوتا ہے.مثلاً دیوار میں اگر کوئی کیل گاڑا جائے تو اس کی غرض کسی چیز کو وہاں لٹکانا ہو گی.گویا وہ کیل دوسرے کے لئے سہارے کا موجب ہوگا.اسی طرح زمین میں جو کِیلے گاڑے جاتے ہیں اُن کی غرض اس کیلے سے کسی دوسری چیز کو باندھنا ہوتی ہے جیسے کسی جگہ خیمہ نصب کرنا ہو تو زمین
Page 21
میں کِیلے گاڑ دیتے ہیں تاکہ اس کے ساتھ خیمے کی رسیاں مضبوطی سے باندھ دی جائیں اور خیمہ کھڑا ہو جائے.یابعض دفعہ گھوڑایا کوئی اور جانور بھی اُس سے باندھ دیتے ہیں.گویاوَتَدٌ کا لفظ کسی چیز کو محفوظ کرنے یا سہارا دینے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے.پس جب خدا نے کہا کہ ہم نے جِبَال کواَوْتَاد بنایا ہے تو اس کے معنے یہ ہوں گے کہ ہم نے جبال کو ایسا بنایا ہےکہ وہ سہارے کا بھی موجب ہیں اور جِبَال زمین کی حرکتِ مُضرہ کو بھی روکنے کا موجب ہیں اور درحقیقت یہی دونوں چیزیں جِبَال کی اغراض میں شامل ہیں.تفسیر.پہاڑوں کے فوائد جہاں تک جِبَال کے فوائد کا سوال ہے یہ امر علوم موجودہ کی رو سے مسلم ہے کہ جِبَال کی وجہ سے ہی زلازل کا آنا بند ہوا.علوم موجودہ کا فیصلہ ہے کہ ہماری زمین کے نیچے بہت بڑی آگ ہے.جب زمین کا چھلکا ابھی پتلا تھا جب بھی اس آگ میں جوش پیدا ہوتا تھا زمین میں سے لاوا نکلنا شروع ہو جاتا.جب وہ لاوا ٹھنڈا ہو جاتا تو پہاڑی کی صورت میںقائم ہو جاتا.پھرا ور لاوا نکلتا اور وہ بھی ٹھنڈا ہو کر پہاڑی بن جاتا.اسی طرح لاوا زمین کے نیچے سے نکلتا چلا گیا اور ٹھنڈا ہو کر بڑے بڑے پہاڑوں کی صورت میں تبدیل ہوگیا.جب زمین کا جوش کافی حد تک نکل گیا تو زمین کا چھلکا موٹا ہو گیا اور زمین آبادی کے قابل ہوئی.پس جبال کیا ہیں وہ زمین کی حرکت مضرہ کو روکنے کا ایک ذریعہ ہیں جیسے گھوڑے کو کیلے کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے اور وہ ادھر ادھر دوڑ نہیں سکتا اسی طرح پہاڑوں کی وجہ سے زمین کی حرکت مضر ہ بند ہوئی اور زلازل کا کثرت کے ساتھ آنا دور ہوا.اسی طرح پہاڑ لوگوں کے لئے سہارے کا بھی موجب ہیں اورہم کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کے تمام ملک انہی پہاڑوں کے سہارے پر لٹکے ہوئے ہیں.پہاڑوں پر برف پڑتی ہے اور لوگوں کے لئے بڑے بڑے فوائد کا موجب ہوتی ہے جب برف پگھلتی ہے تو زمین میں نالے بہ نکلتے ہیں.دریا جاری ہو جاتے ہیں اور پھر ان دریاؤں میں سے نہریں نکالی جاتی ہیں اور اس طرح تمام ملک سیراب ہو جاتا ہے.اسی طرح پہاڑی چشمے لوگوں کی سیرابی کا موجب بنتے ہیں.گویا پہاڑ ان دونوں اغراض کو پورا کر تے ہیں وہ زمین کی حرکت مضرہ کو بھی روکتے ہیں اور ان کےذریعہ تمام ملکوں کو ایک سہارا بھی مل جاتا ہے چنانچہ پہاڑوں سے ہی پانی میسر آتا ہے جو ملکوں کی سیرابی اور بنی نوع انسان کی زندگی کے کام آتا ہے.
Page 22
وَّ خَلَقْنٰكُمْ اَزْوَاجًاۙ۰۰۹ اور (پھر )ہم نے تم (سب لوگوں) کو جوڑا (جوڑا) بنایا ہے.حل لغات.اَ زْوَاجًا: اَزْوَاجٌ زَوْجٌ کی جمع ہے اور زَوْجٌ کے معنے ہیں کُلّ وَاحِدٍ مَعَہٗ اٰخَرُ مِنْ جِنْسِہٖ.ہر ایک وہ چیز جس کے ساتھ اس کی جنس میں سے ایک اور وجود بھی ہو.اَلصِّنْفُ مِنْ کُلِّ شَی ئٍ.ہر چیز کی قسم.صنف.اَلْبَعْلُ.خاوند.اَلزَّوْجَۃُ.بیوی.(اقرب) تفسیر.وَ خَلَقْنٰكُمْ اَزْوَاجًاکی پہلی تشریح فرماتا ہے اِدھر ہم نے یہ سامان پیدا کر دیا کہ زمین کو ہم نے ایسا بنایا جسے تم بستر کے طور پر استعمال کرتے ہو.پھر ہم نے پہاڑوں کو بنایا جو تمہارے لئے سہارے کا بھی موجب ہیںاور وہ زمین کی حرکت مُضِرہ کو بھی روکنے کا ذریعہ ہیں دوسری طرف ہم نے تمھارے اندر یہ بات رکھ دی ہے کہ خَلَقْنٰکُمْ اَزْوَاجًا.ہم نے تم کو زَوْج بنایا ہے.زَوْجٌ کے معنے جوڑے کے ہوتے ہیںچنانچہ نر کو بھی زوج کہتے ہیںاور مادہ کو بھی زوج کہتے ہیں.ہمارے ملک میں جس کو زوجہ کہتے ہیں عربی زبان میں اُسے زَوْج بھی کہہ سکتے ہیں اور زَوْجَۃ بھی کہہ سکتے ہیں.ایک انسان اپنی بیوی کے متعلق یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ ھِیَ زَوْجِیْ یہ میری بیوی ہے یہ ضروری نہیں کہ وہ ھِیَ زَوْجَتِیْ کہے.اسی طرح زوج کا لفظ مرد کے لئے بھی استعمال ہو سکتا ہے چنانچہ ایک عورت اپنے خاوند کے متعلق بھی کہہ سکتی ہے کہ ھُوَ زَوْجِیْ پس خَلَقْنٰکُمْ اَزْوَاجًا کے معنے یہ ہوئے کہ خدا نے تم کو جوڑا بنایا ہے یعنی نر و مادہ کی صورت میں اس نے تم کوپیدا کیا ہے گویا ایک طرف زمین میں یہ قابلیت رکھی ہے کہ تم اس کی طرف اُسی طرح لوٹتے ہو جیسے بستر کی طرف جس طرح انسانی جسم میں جب تھکان پیدا ہو جائے تو وہ آرام کے لئے اپنے بستر کی طرف جاتا ہے اسی طرح جب بھی تمہیں کوئی ضرورت محسوس ہوتی ہے یا تمہیں کسی تکلیف کا احساس ہوتا ہے تم زمین کی طرف توجہ کرتے ہواور تمہیں اپنی تمام ضروریات زمین میںسے حاصل ہو جاتی ہیں مثلاً غذا ہے انسان کو کھانے کے لئے جس چیزکی بھی ضرورت ہو زمین سے وہ مہیا ہو جاتی ہے.اسی طرح لباس ہے اللہ تعالیٰ انسان کی اس ضرورت کوبھی زمین سے ہی پورا کرتا ہےغرض انسان جب بھی کوئی ضرورت محسوس کرتا ہے.زمین سے اللہ تعالیٰ اس کی وہ ضرورت پوری کر دیتا ہے اور وہ اسی طرح زمین سے آرام حاصل کرتا ہے جس طرح بستر سے انسانی جسم راحت حاصل کرتا ہے.پھرجِبَال بھی زمین کے لئے تقویّت اور سہارے کا موجب ہیں.درحقیقت زمین میں بعض نقائص ایسے تھے جن کے ازالہ کے لئے اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کا سلسلہ جاری کر دیا.اگر پہاڑ نہ ہوتے توزمین
Page 23
کئی فوائد سے محروم رہ جاتے.مثلاًپہاڑوں کا یہ بہت بڑا فائد ہ ہے کہ وہ اس پانی کو جو زمین کی زندگی کا ذریعہ ہے جمع رکھتے ہیں کیونکہ برف پہاڑ کی چوٹیوں پر ہی پڑتی ہے اور پھر وہ برف پگھل کر زمین کے لئے سال بھر کے لئے پانی مہیا کر دیتی ہے.اسی طرح قسم قسم کی بُوٹیاں ہیں جو پہاڑوں پر پیدا ہوتی اور بنی نوع انسان کے کام آتی ہیں.زمین کو انسان چونکہ اپنی رہائش کے لئے آباد کرتا ہے اس لئے وہ پروا نہیں کرتا کہ زمین کو قابل رہائش بنانے کے لئے وہ کون کون سی چیزیں تلف کر رہا ہے جب بھی اُسے اپنی رہائش کے لئے یا اپنے اور کاموں کے لئے زمین کی ضرورت محسوس ہوتی ہے وہ بلا دریغ اُن سب چیزوں کو تلف کر دیتا ہے جو زمین پر موجود ہوتی ہیں.اگر درخت اُگے ہوئے ہوں تو ان کو کاٹ دیتا ہے بوٹیاں موجود ہوں تو اُن کو اُکھیڑ دیتا ہے کیونکہ اُسے ضرورت ہوتی ہے کہ اپنی رہائش کے لئے زمین کو صاف کرے.پس چونکہ زمین کو انسان نے آباد کرنا تھا اس میں اپنی رہائش کے لئے اُس نے مکان بنانے تھے.سڑکیں بنانی تھیں.کھیت بونے تھے.رستے تیا ر کرنے تھے اور یہ چیزیں تقاضا کرتی تھیں کہ زمین صاف ہو اس لئے انسانی عادت میں یہ بات داخل ہے کہ وہ زمین کو بالکل صاف کر دیتا ہے اور تما م روئیدگیوں وغیر ہ کولغو سمجھ کر کاٹ دیتا ہے.حالانکہ ان بوٹیوں میں جن کو کاٹ رہا ہوتا ہے اور جن کو وہ بالکل لغو اور بیکا ر سمجھ رہا ہوتا ہے ہزاروں بوٹیاں ایسی ہوتی ہیں جو نہایت ہی مفید ہوتی ہیں اور کئی قسم کی بیماریوں کو دُور کرنے کاذریعہ ہوتی ہیں پس اگر میدان ہی میدان ہوتے تو اس کالازمی نتیجہ یہ ہوتا کہ انسان ساری چیزیں اُکھیڑ دیتا.حالانکہ اُن میں بیسیوں چیزیں ایسی ہو سکتی تھیں جو اس کے لئے نہایت مفید ہوتیں.اس نقص کودُور کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے پہاڑ بنا دئیے ہیں.وہاں جس طرح پانی محفوظ ہوتا ہے (کیونکہ برف پہاڑوں پر ہی پڑتی ہے) اسی طرح ہزاروں قسم کی بوٹیاں جو انسانی صحت کے لئے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہیں اور جو اگر ہموار زمین پر ہوتیں تو انسان اُن کو کاٹ کر فنا کر چکا ہوتا وہاں محفوظ رہتی ہیں اس طرح پہاڑ زمین کے لئے سہارے کا موجب بن جاتے ہیں.ان امور کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَّ خَلَقْنٰكُمْ اَزْوَاجًا.ہم نے تمہیں نر اور مادہ بنایا ہے جس کی وجہ سے تمہاری نسل چلتی ہے.یعنی ایک طرف زمین میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لئے بے انتہا فوائد جو زمینی قوتوں کو مدنظر رکھتے ہوئے نہ ختم ہونے والے ہیں رکھے ہیں اور دُوسری طرف اُس نے جِبَال بنائے ہیںجن سے یہ فوائد عملی صورت میں بھی مستقل ہو جاتے ہیں.گویا زمین بھی فائدے کا موجب ہے اورجِبَال بھی فائد ے کا موجب ہیں.فرق صرف یہ ہے کہ جِبَال زمین کے فوائد کو مستقل حیثیت دےدیتے ہیں پس ایک طرف تو اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم الشان سلسلہ تمہارے لئے جاری کیا ہوا ہے دوسری طرف تمھار ی نسل قائم کرنے کے لئے اس نے تمہیں اَزْوَاج یعنی نر و مادہ بنا دیا ہے.اب کیا
Page 24
یہ عجیب بات نہیں کہ خدا نے تمہارے لئے ایک طرف تو زمین کو پیدا کیا جس سے تم اپنے کھانے کا سامان حاصل کرتے ہو اپنے پینے کا سامان حاصل کرتے ہو.اپنے لباس کا سامان حاصل کرتے ہو.اپنی رہائش کا سامان حاصل کرتے ہو.اور دُوسری طرف اُس نے پہاڑ بنا دیئے جن سے یہ فوائد ایک مستقل صورت اختیار کر گئے ہیں تیسری طرف اُس نے تمہیں نر و مادہ بنا دیا تا کہ تمہاری نسل قائم رہے اور مستقل صورت اختیار کرے اور تم ان چیزوں سے ہمیشہ فائدہ اُٹھاتے رہو.مگر تمہاری یہ حالت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس لمبے سلسلہ ٔ پیدائش کے متعلق تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ سب لغو اور فضول ہے ان کی پیدائش کسی حکمت پر مبنی نہیں.خَلَقْنٰكُمْ اَزْوَاجًا کی دوسری تشریح زَوْج کے ایک معنے صِنف کے بھی ہوتے ہیں اس لحاظ سے خَلَقْنٰكُمْ اَزْوَاجًا کا یہ مفہوم ہو گا کہ ہم نے تم کو مختلف اقسام میں پیدا کیا ہے یعنی کوئی شخص تم میں سے ایسا ہے جو تصویر کشی کی رغبت رکھتا ہے.کوئی ایسا ہے جو نجّار بننے کی قابلیت رکھتا ہے.کوئی ایسا ہے جسے سائنس میں انہماک ہے.کوئی ایسا ہے جو حساب سے دلچسپی لیتا ہے کوئی ایسا ہے جو تاریخ کی طرف مائل ہے.غرض ہم نے تم کو مختلف اقسام میں تقسیم کر دیا ہے.اگر سب طبائع یکساں ہوتیں تو دنیا ایک ہی حالت میں چلتی چلی جاتی اور اُس میں کسی قسم کی ترقی نہ ہوتی.مگر ہم نے انسانی دماغ کو اتنا متنوّع بنا یا ہے اور اس قدر اقسام در اقسام صورت میں ترقیات کا میدان اس کے لئے کھولا ہے کہ ہر شخص اپنے اپنے مذاق اور اپنی اپنی طبیعت کے مطابق جس لائن کو چاہتا ہے اختیار کر لیتا ہے.کوئی دنیا میں مشغول ہے کوئی دین میں مشغول ہے کوئی سائنس کی طرف توجہ کر رہا ہے.کوئی علم الاخلاق میں ترقی کر رہا ہے.کوئی علم ہندسہ میں سبقت لے جانا چاہتا ہے کوئی تاریخ سے اپنی دلچسپی کا اظہار کر رہا ہے.غرض اپنے اپنے رنگ میں انسانی فطرت اس میدان میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی ہے.یہ تنوّع اس بات کی دلیل ہے کہ انسان میں خدا تعالیٰ نے کسی غیر مرئی چیز کو پا لینے کی رغبت پیدا کی ہے اور اس کے اندر یہ تڑپ رکھی ہے کہ وہ اس مخفی اور غیر مرئی چیز کو حاصل کرنے کی جدّوجہد کرے.چنانچہ اس کوشش اور تلاش میں کوئی کسی طرف دوڑ رہا ہے اور کوئی کسی طرف دوڑ رہاہے جیسے پانی جب بہایا جاتا ہے تو وہ نشیب کی طرف بہہ پڑتا ہے اسی طرح انسانی طبیعت اپنے اپنے مذاق کے مطابق مختلف رستوں پر دوڑ رہی ہے.کوئی کسی رستہ سے اس چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے اور کوئی کسی رستہ سے.یہ ایسی ہی بات ہے جیسے کسی خاندان کا بچہ کھویا جائے تو اس خاندان کے کچھ افراد مشرق کو چل پڑیں گے کچھ مغرب کی طرف چلے جائیں گے.کچھ شمال کی طرف دوڑ پڑیں گے اور کچھ جنوب کی سمت اختیارکرلیں گے مگر مقصد سب کا ایک ہی ہو گا کہ کسی طرح اس بچہ کو ڈھونڈا جائے.اسی طرح انسانی فطرت مختلف رستوں پر مختلف جہات کی طرف بھاگ
Page 25
رہی ہے جو ثبوت ہے اس بات کا کہ کوئی چیز ایسی ہے جس کے متعلق فطرت یہ محسوس کرتی ہے کہ اُسے حاصل کرنا چاہیے.مگر چونکہ اُسے علم نہیں کہ وہ کہاں ہے اس لئے مختلف جہات سے وہ اس چیز کو پکڑنے کی کوشش کرتی ہے یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ انسانی فطرت اپنے لئے کسی ایسے مقصود کی طالب ہے جس کے مقام کا علم خود اُسے اپنی ذات کے اندر سے نہیں حاصل ہوتا اور چونکہ اُسے اپنی ذات سے اُس کے مقام کا علم حاصل نہیں ہوتا اس لئے وہ مختلف جہات سے اس کو تلاش کرنے کی کوشش کرتی ہے اور یہ حالت چلتی چلی جاتی ہے یہاں تک کہ خدا تعالیٰ اپنا کلام نازل کرکے اس مقصد کو ظاہر کردیتا ہے پھر انسان کی تسلی ہو جاتی ہے اور وہ سمجھ لیتا ہے کہ وہ مقصد میں نے پا لیا جس کے لئے میں کوشش کر رہا تھااور جس کے لئے خدا نے مختلف قسم کے مادے انسانی فطرت میں پیدا کئے تھے.انسانوں کو مختلف الطبائع پیدا کر نا بعث بعد الموت پر دال ہے گویا ایک طرف زمین اور جبال کی پیدائش کا سلسلہ اور دوسری طرف انسانی فطرت میں تنوّع کا پایا جانا ا ور مختلف الطبائع انسانوں کا مختلف جہات کی طرف اپنے مقصد کے حصول کے لئے دوڑنا یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ انسان کے سامنے کوئی بہت بڑا مقصدہے جس کے حصول کے لئے اُس نے کوشش کرنی ہے پس انسانی فطرت کی یہ کشمکش ایک طرف کلام الٰہی کی ضرورت پر دلالت کرتی ہے دوسری طرف بعث بعد الموت پر دلالت کرتی ہے اور تیسری طرف کلام الٰہی کے نزول کے بعد اس کے غلبہ پر بھی دلالت کرتی ہے کیونکہ اگر کلامِ الٰہی کا غلبہ نہیں ہونا تھا تو پھر اُس کے نزول کا کوئی فائدہ نہ تھا پس یہ امر کلام الٰہی کے غالب آنے پر بھی دلالت کرتا ہے.خلاصہ یہ کہ زمین جس پر انسان بستا ہے اس میں بے انتہاء اشیاء اور قوتیں پیدا کر کے اور پہاڑوں کے ذریعہ سے خورونوش اور سائنٹفک ترقیات کے سامانوں کو مستقل رنگ دے کر اور انسانوں کو اس صورت میں پیدا کر کے کہ وہ مختلف مزاجوں کے مطابق زمین کی مختلف قابلیتوں کو ترقی دیں اور اُن سے فائدہ اُٹھائیں.اور پھر انسان کو بھی مرد وزن بنا کر اور ایک مستقل قائم رہنے والے وجود کی شکل دے کر اللہ تعالیٰ نے ثابت کر دیا ہےکہ انسان غیر محدود ترقیات کے لئے اور دائمی زندگی کے لئے پیدا کیا گیا ہے اور اگر یہ بات ثابت ہے تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اس دنیا میں فنا ہو نے والے انسان کے لئے کسی اور دنیا میں دائمی زندگی کا سامان مہیا ہونا چاہیے اور اس دائمی زندگی کے لئے کوئی ہدایت نامہ اور اس ہدایت نامہ پر چلنے والوں کے لئے کامیابی کی ضمانت بھی ہونی چاہیے.ورنہ کارخانۂ عالم بیکار محض ثابت ہوتا ہے.
Page 26
وَّ جَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًاۙ۰۰۱۰ اور ہم نے تمھاری نیند کو موجب راحت بنا یا ہے.حل لغات.سُبَات سُبَاتٌ سَبْتٌ سے ہے اور سَبْتٌ کے اصل معنے کسی چیز کو کاٹنے کے ہیں چنانچہ کہتے ہیں سَبَتَ السَّیْرَ چمڑے کے ٹکڑے کو لمبے رنگ میں کاٹا.وَسَبَتَ شَعْرَہٗ: حَلَقَہٗ اُس نے بالوں کو کاٹا.اور ہفتہ کو یومِ سبت اس لئے کہا گیا کہ اُس دن یہودی اپنے کام کاج چھوڑ دیتے تھے (مفردات ) انہی معنوں کے پیش نظر وَجَعَلْنَا نَوْمَکُمْ سُبَاتًا کے معنے صاحب مفردات نے کئے ہیں قَطْعًا لِلْعَمَلِ کہ ہم نے تمھاری نیند کو ایسا بنایا ہے کہ اُس سے تم اپنے کاموں سے کٹ جاتے ہو اور پھر تازہ دم ہو جاتے ہو (مفردات ) اقرب الموارد میں ہے اَلسُّبَاتُ: الدَّھْرُ یعنی زمانہ اَلدَّاھِیَۃُ مِنَ الرِّجَالِ.آدمیوں میں سے بڑا لائق آدمی.اَلنّوْمُ.نیند.وَقِیْلَ خِفَّتُہٗ وَقِیْلَ اِبْتَدَاءُ ہٗ فِی الرَّاسِ حَتّٰی یَبْلُغَ الْقَلْبَ بعض کے نزدیک سُبَات کے معنے ہلکی سی نیند کے ہیں اور بعض نے اس کے معنے اُونگھ کے کئے ہیں لیکن اقرب الموارد کے مصنف لکھتے ہیں وَاَصْلُہُ الرَّاحَۃُ کہ اس کے اصل معنے آرام اور راحت کے ہیں (اقرب ) تفسیر.فرماتا ہے ہم نے تمھاری نیند کو سُبَات بنایا یعنی اگر کوئی شخص کہے کہ اسلام کے ذریعہ کُفر پر ایک نئے غلبہ کی کیا ضرورت ہے اگر کفر پر غلبہ ہی منشاء ہے تو آدم ؑ کے وقت یہ غلبہ ہو گیا.نوح ؑکے وقت یہ غلبہ ہو گیا.اب کسی نئے غلبہ کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس کے جوا ب میں فرماتا ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَکُمْ سُبَاتًا کیا زندگی میں تم دیکھتے نہیں کہ ایک جاگنے کا وقت ہوتا ہے اور ایک سونے کا وقت ہوتا ہے.اسی طرح قوموں میں بیداری اور نیند کاایک تسلسل چلا جاتا ہے تا کہ نئی قوتیں لے کر انسان اُٹھے اور کفر کو شکست دینے کے لئے کھڑا ہو جائے.اس طرح لوگ ایک لمبے عرصہ تک کوشش کرتے چلے جاتے ہیں.مگرجب وہ اپنی ان کوششوں میں تھک جاتے ہیں جب ان کی تمام رغبتیں دنیا میں محدود ہو جاتی ہیں جب دین کی طرف سے وہ بے رغبتی کا اظہار کرنے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اُن کو چھوڑ دیتا ہے اُن کی حالت بدل جاتی ہے اور وہ خرابیوں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں تب اللہ تعالیٰ ایک نیا فضل نازل کرتا اور لوگوں کی ہدایت کے لئے ایک نئے رُوحانی سورج کا طلوع کرتا ہے.َ جَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا کے معنے اس آیت میں چونکہ نَوْم کا لفظ مذکور ہے اس لئے سُبَاتًا سے مراد نیند تو نہیں ہو سکتی جو اس کے معروف معنےہیں اور حل لغات میں بیان ہو چکے ہیں.پس لازمًااس کے کوئی اور معنے ہوں گے اور
Page 27
وہ معنے یہی ہیں کہ جَعَلْنَا نَوْمَکُمْ رَاحَۃً ہم نے تمہاری نیند کو ایک راحت کا ذریعہ بنایا ہے اور چونکہ سُبَات کے ایک معنے دَھْر کے بھی ہوتے ہیںاس لئے جَعَلْنَا نَوْمَکُمْ سُبَاتًا کے معنے جَعَلْنَا نَوْمَکُمْ دَھْرًا کے بھی ہوسکتے ہیں.یعنی تمہاری نیند کے زمانہ کو ایک لمبا زمانہ بنایا ہے.اس صورت میں نیند سے مراد وہ زمانہ ہو گا جب روحانی سورج کا طلوع نہیں ہوتا اور قوم غفلت کی حالت میں سو رہی ہوتی ہے گویا مراد یہ ہے کہ جب کوئی قوم سوتی ہے تو پھر ایک لمبے عرصہ تک سوتی چلی جاتی ہے.وَّ جَعَلْنَا الَّيْلَ لِبَاسًاۙ۰۰۱۱ اور ہم نے رات کو پردہ پوش بنایا ہے.حل لغات.لِبَاس لِبَاسٌ کے معنے مفردات میں یوں لکھے ہیں وَجُعِلَ اللِّبَاسُ لِکُلِّ مَا یُغَطِّیْ مِنَ الْاِنْسَانِ عَنْ قَبِیْحٍ یعنی لباس کا لفظ ہر ایسی چیز پر بولا جاتا ہے جو انسانی عیوب اور نقائص کو چھپا دیتی ہے پس جَعَلْنَا الَّیْلَ لِبَاسًا کے معنے یہ ہوںگے کہ ہم نے رات کو تمہاراننگ ڈھانکنے والی چیز بنایا ہے اور اسی لحاظ سے رات کو لباس قرار دیا گیا ہے کیونکہ عربی زبان میںہر وہ چیز جو عیوب ڈھانکنے کا کام دے وہ لباس کہلاتی ہے جیسے قرآن کریم میں ہی ایک دوسرے مقام پر لِبَاسُ التَّقْویٰ (الاعراف :۲۷ ) کے الفاظ استعمال کئے گئے ہیں.تقویٰ کو بھی لباس انہی معنوں میں کہا گیا ہے کہ تقویٰ انسانی عیوب کو ڈھانکتا ہے پس اللہ فرماتا ہے ہم نے رات کو تمہارے عیوب ڈھانکنے والی چیز بنایا ہے.اقرب ؔمیں ہے اَلِلّبَاسُ: اَلْاِخْتِلاطُ وَالْاِجْتِمَاعُ یُقَالُ ’’ بَیْنَہُمْ لِبَاسٌ‘‘ اَیْ اِخْتِلَاطٌ وَ اِجْتِمَاعٌ (اقرب)یعنی اختلاط اور اجتماع کو بھی لباس سے تعبیر کرتے ہیں چنانچہ عرب کہتے ہیں بَیْنَہُمْ لِبَاسٌ اور مراد یہ ہوتی ہے کہ اُن کے درمیان اختلاط اور اجتماع ہے.لسانؔ میں ہے لِبَاسُ کُلِّ شَیْ ئٍ غِشائُ ہٗ.ہر چیز کا پردہ اُس کا لباس کہلاتا ہے.تفسیر.رات کو لباس بنانے کا مطلب اگر رات نہ آئے اور انسان ہر وقت جاگتا رہے تودوچار دن میں ہی وہ پاگل ہو جائے مگر رات آنے کی وجہ سے انسان کا یہ نقص ظاہر نہیں ہوتا.کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رات کو بنی نوع انسان کا لباس بنایا ہے اور وہ انسان کی محدود طاقت کے نقائص کو چھپا دیتی ہے.اس طرح رات کے
Page 28
اندھیرے میں جب کوئی شخص سویا ہوا ہوتو اس کے سوتے وقت کے نقائص دوسروں کو معلوم نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ بھی سوئے ہوئے ہوتے ہیں اور کوئی دوسرا شخص ان نقائص کو دیکھ نہیں سکتا لیکن اگر دن کے وقت کوئی شخص سوئے تو دوسرے شخص کو فوراًاس قسم کے عیوب نظر آجائیں.سوتے وقت انسان کی عجیب عجیب حالتیں ہوتی ہیں اور بعض تو یقیناً ایسی ہوتی ہیں جن کو اگر دوسرا شخص دیکھ لے تو اُسے سخت کراہت آئے بعض دفعہ ایک بڑا شخص ہوتا ہے لیکن اُس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ جب وہ سوتا ہے تو اُس کا منہ کُھلا رہتا ہے اور اُس پر مکھیاں بیٹھتی ہیں.لیکن اگر وہ رات کو سوتا ہے تو اس کا یہ نقص پوشیدہ رہتا ہے اسی طرح بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ سوتے وقت خراٹے شروع کر دیتے ہیں.بعض نہایت قابلِ نفرت طریق پرسوتے ہیں.کوئی بلّی کی طرح سوتا ہے کوئی مچھلی کی طرح سوتا ہے اور کوئی کسی طرح سوتا ہے.غرض سونے کی ایسی ایسی حالتیں ہوتی ہیں جن کو دیکھ کر گھِن پیدا ہوتی ہے.رات عیوب کے ڈھک جانے کا ایک ذریعہ پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا الَّیْلَ لِبَاسًا ہم نے رات کو لباس بنایا ہے یعنی سونے کا عام وقت رات ہوتا ہے اور رات میں سونے والوں کے جسمانی عیوب ڈھک جاتے ہیں.اگر انسان عام طور پر دن کو سوتا تو اس کے عیب ظاہر ہو جاتے لیکن چونکہ وہ رات کے اندھیرے میں سوتا ہے اس لئے اُس کے سوتے وقت کے عیوب کا پتہ نہیں لگتااوررات اُن پر پردہ ڈال دیتی ہے.روحانی لیل لوگوں کے لئے بطور لباس کے اسی طرح روحانی لَیْل بھی ایک لباس ہوتی ہے کیونکہ رات اسی کو کہتے ہیں جب سارے لوگ سوئے ہوئےہوں جس طرح جسمانی لَیْل لباس کا کام دیتی ہے.اسی طرح روحانیلَیْل بھی لباس کا کام دیتی ہےکیونکہ ساری قوم مُردہ ہوتی ہے کوئی شخص کسی دوسرے کا کوئی عیب نہیں دیکھتا جیسے کہتے ہیں حمام میں سارے ننگے.اُس زمانہ میں بھی روحانی لحاظ سے سب ننگے ہوتے ہیں.ہر شخص میں بدی ہوتی ہے.ہر شخص میں عیب ہوتا ہے اور چونکہ ہر شخص گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے اس لئے کسی دوسرے کا گناہ اُسے نظر نہیں آتا.جیسے اسلام سے پہلے جاہلیت کے زمانہ میں ہر شخص شرک میں مبتلا تھا.فرق صرف اتنا تھا کہ کوئی بڑا مشرک تھا اور کوئی چھوٹا مشرک تھالیکن باجود اس کے کہ ہر شخص شرک میں مبتلا تھا کوئی شخص دوسرے کے نقص کا اظہار نہیں کرتا تھا.جب نبی آتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے روحانی سورج کا طلوع کر دیتا ہے تو پھر لوگوں کو ایک دوسرے کے نقائص نظر آنے لگ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں فلاں ایسا ہے اور فلاں ایسا ہے مگر جب تک سب قوم سوئی ہوئی ہو کوئی شخص دوسرے کے عیب کونہیں دیکھ سکتا.جیسے یورپ میں ننگے ناچ ہوتے ہیں مگر کسی کے دل میں یہ احساس پیدا نہیں ہوتا کہ یہ بھی کوئی گندی چیز ہے کیونکہ روحانی لَیْل اُن پر چھائی ہوئی ہے اور رات کی تاریکی کی وجہ سے اُنہیں یہ نقائص نظر نہیں
Page 29
آتے.بڑے سے بڑا آدمی بھی ان نظاروں کو دیکھےگا تو خاموشی سے گذر جائے گا اور اُسے یہ خیال نہیں آئے گاکہ ان باتوں کے خلاف نفرت کااظہار کرے.مگر جب نبی کا زمانہ آتا ہے تو پھر لوگ شرمانے لگتے ہیںاور وہ کہنے لگ جاتے ہیںکہ یہ بھی بُری بات ہے اور وہ بھی بُری بات ہے.پھرلباس زینت کا موجب بھی ہوتا ہے اور کام کرنے والوں کے لئے ایک رنگ میں رات ہی زینت کا باعث ہوتی ہے.عرب میں رواج ہے کہ غریب سے غریب آدمی بھی روزانہ اپنے کپڑے دھوتا ہے یا بعض امیر لوگ رات کو اور کپڑے پہنتے ہیں اور دن کو اَور.دن میں تو کام کاج کرنے کی وجہ سے لباس خراب ہو جاتا ہے لوگ اچھا لباس نہیں پہن سکتے مگر رات کو فارغ ہو کر پہنتے ہیں اور آرام سے بیٹھتے ہیں.بعض ممالک یعنی یورپ وغیر ہ میں جا کر دیکھ لو امیر سے امیر آدمی دن کے وقت کارخانوں وغیرہ میں کام کر رہے ہوتے ہیں اور چار چار سو پانچ پانچ سو تنخواہ پر ملازم ہوتے ہیں لیکن لباس خراب ہوتا ہے.لیکن جہاں چار بجے اور کام سے فارغ ہوئے غسل کر کے صاف ستھرے کپڑے پہن لیتے اور آرام سے اپنے گھر بچوں اور بیوی کے پاس بیٹھتے ہیں.وَّ جَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۪۰۰۱۲ اور ہم نے دن کو زندگی ( کے اظہار) کا ذریعہ بنایا ہے.حل لغات.مَعَاشًا مَعَاشٌ عَاشَ کا مصدر ہے اور عَاشَ یَعِیْشُ مَعَاشًا کے معنے ہوتے ہیں صَارَذَا حَیَاۃٍ (اقرب ) یعنی وہ زندہ ہوا.پس مَعَاشَ کے معنے ہوئے زندگی والا ہونا.اور جَعَلْنَا النَّھَارَ مَعَاشًا کا یہ مطلب ہوا.کہ ہم نے دن کو حیات کے اظہار کا ایک موقع بنایا ہے.اسی طرح لغت میں مَعَاشًا کے ایک معنے یہ بھی لکھے ہیں کہ مُلْتَمَسًا لِلْعَیْشِ (اقرب) اس صورت میں جَعَلْنَا النَّھَارَ مَعَاشًا کے معنے یہ ہوں گے کہ ہم نے دن کو ایسا بنایا ہے کہ اُس میں انسان اپنے عیش کے سامان تلاش کرتا ہے گویا جَعَلْنَا النَّھَارَ مَعَاشًا کے ایک معنے ہوئے دن کو ذوحیات بنایا ہے اور دوسرے معنے ہوئے مُلْتَمَسًا لِلْعَیْشِ یعنی دن ایک ذریعہ سامانِ معیشت کے تلاش کا ہوتا ہے.نہار کو معاش بنانے کا مطلب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرماتا ہے کہ ہم نے دن کو ایک حیات کی چیز بنایا ہے یعنی دن اپنی ذات میں حیات کو ظاہر کرنے والا اور وہ زندہ چیز نظر آتی ہے.دوسرے معنے یہ ہوںگے
Page 30
کہ ہم نے نہار کو ذریعہ عیش بنایا ہے یعنی وہ انسان کے لئے زندگی کے سامان تلاش کرنے کا ایک ذریعہ ہے.اس کے علاوہ اگر مَعَاشًا کو مبالغہ کے معنوں میں لیا جائے تو یہ جَعَلَ کا مفعول بہٖ بن جاتا ہے.اس کی ایسی ہی مثال ہو گی جیسے کہتے ہیں زَیْدٌ عَدْلٌ پس علاوہ مفعول فیہ ہونے کے یہ اس کے مفعول بہٖ کے طور پر بھی استعمال ہو سکتا ہے کہ ہم نے نھار کو معاش بنا دیایعنی نھاراور معاش کا آپس میں اتنا گہرا تعلق ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ معاش نھار ہے اور نھارمعاش ہے تو یہ بالکل جائز ہے جیسے کہتے ہیںزَیْدٌ عَدْلٌ یعنی زید کا عدل سے اتنا گہرا تعلق ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ زید عدل ہےاور عدل زید ہے تو یہ جائز ہو گا.قرآن کریم میں بھی اس کی مثال پائی جاتی ہے سورۂ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَ اِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ(العنکبوت :۶۵) حَیْوَان کا لفظ یہاں حیات کے مبالغہ کے طور پر استعمال ہوا ہے اور مطلب یہ ہے کہ دارِ آخرت ہی اصل زندگی ہے.اب دارِ آخرت ایک جگہ کا نام ہے اور کوئی خاص جگہ زندگی نہیں کہلا سکتی مگر چونکہ انسان دارِ آخرت میں ہی حقیقی طور پر زندہ ہو گا اور اصل زندگی وہی ہے جو انسان کواگلے جہان میں حاصل ہوگی اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ دارِ آخرت ہی زندگی ہے.یعنی اگرہم یہ کہیں کہ دارِ آخرت کی زندگی ہی حقیقی زندگی ہے تو یہ بالکل جائز ہے.نہار اور معاش کا گہرا تعلق پس جَعَلْنَا النَّھَارَ مَعَاشًا کے یہ معنے ہوں گے کہ معاش کا دن کے ساتھ اتنا بھاری تعلق ہے اور رات کے ساتھ معاش کا اتنا کم تعلق ہےکہ اگر ہم یہ کہیں کہ خدا تعالیٰ نے دن کو معاش بنا دیا ہے یعنی دن میں اُس نے اتنےسامان معاش کمانے کے پیدا کر دئیے ہیں کہ اور کسی وقت وہ سامان میسَّر نہیں آ سکتے تو یہ بالکل درست ہو گا.یہ معنے مَعَاشًا کے مفعول بہٖ ہونے کی صورت میں ہیں لیکن اگر اسے مفعول فیہ سمجھا جائے تو اس کے معنے وقتِ معاش کے ہوں گے یعنی دن کو ہم نے ایک ذریعۂ معاش بنا دیا ہے.دوسرے اوقات میں انسان معاش کو تلاش نہیںکر سکتا لیکن دن اُس کے حصولِ معاش کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے.مَعَاشًا کے دو معنے مَعَاشًادرحقیقت عَاشَ کا مصدر ہے اور مَعَاشَ کے معنے ایک تو محض حیاۃٌ کے ہوتے ہیں اور دوسرے معنے حیوانی حیات کے ہوتے ہیں.عام معنے اس کے حیوانی حیات کے ہی ہوتے ہیں.یہ مطلب نہیں کہ اس کے کوئی بُرے معنے ہیں بلکہ حیوانی حیات سے مراد صرف وہ زندگی ہے جو کھانے پینے سے تعلق رکھتی ہے.تفسیر.اِن آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون بیان فرمایا ہے کہ جس طرح دن کے بعد رات آتی ہے اسی طرح قوموں پر بھی بعض دفعی تاریکی کا دَور آجاتا ہے اور وہ تاریکی کادَور اُن کے لئے ایسا ہی ہوتا ہے جیسے نہار کے بعد لیل کی ظلمت دنیا پر چھا جاتی ہے.
Page 31
آیت جَعَلْنَا النَّھَارَ مَعَاشًا سے بعث بعد الموت پر ثبوت میں نے بتایا تھا کہ اس سورۃ میں تین مضامین کا ذکر ہو رہا ہے قیامت کا.غلبۂ قرآن کا اور غلبۂ اسلام کا.پس اگر یہاں بعث بعدالموت مراد ہو تو اس صورت میں وَجَعَلْنَا الَّیْلَ لِبَاسًا کا مفہوم یہ ہو گا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے رات کو تمہارے نقائص دور کرنے کے لئے پیدا کیا ہے.تمہاری روح میں یہ قابلیت نہیں تھی کہ وہ ہمیشہ نھارسے فائدہ حاصل کر سکتی بلکہ ضروری تھا کہ اُس پر رات بھی آتی تاکہ دن سے فائدہ اُٹھانے کے لئے اُس میں نئی طاقتیں پیدا ہو جاتیں یہی تمہارا روحانی حال ہے جس طرح خدا نے تمہارے لئے رات کو لباس اور نیند کو سُبَات بنایا ہے اسی طرح خدا تعالیٰ نے دنیا کی پیدائش کا سلسلہ جو لَیْلاور سُبَات کا قائم مقام ہے اس لئے جاری کیا ہے تاکہ تم اس جہان میں رہ کر اپنے اند ر وہ نئی طاقتیں پیدا کرو جن سے اگلے جہان میں تمہیں رؤیت الٰہی نصیب ہو سکے پس جس طرح لیل کا نہار سے پہلے آنا ضرور ی ہے اسی طرح تمہاری ترقی کے لئے ایک اور عالم کا ہونا بھی ضروری ہے تم اس جہان میں رہ کر اپنے اندر وہ قابلیتیں پیدا کرو تاکہ اگلے جہان میں رؤیت الٰہی سے حصہ لے سکو.اور اگرقرآن یا اسلام کا غلبہ مراد ہو تو اس صورت میں مذکورہ بالا آیت کے یہ معنے ہوں گے کہ تمہاری قوم سو رہی تھی مگر اللہ تعالیٰ اسی لَیْل میں تمہارے اندر نئی قوتیں پیدا کر رہا تھا.جب بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے کلام نازل ہوتا ہے اُسی قوم میں نازل ہوتا ہے جو مردہ اور ذلیل ہو چکی ہوتی ہے تاکہ وہ اُس کلام کے ذریعہ نئی طاقتیں لے کر کھڑی ہو جائے اور دنیا پر غالب آجائے.یہی وجہ ہے کہ جب بھی خدا تعالیٰ کا کلام کسی قوم میں نازل ہوتا ہے اُس کی قوتوں میں نشوونما پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور آخر ایک دن وہ قوم اُن قوتوں سے کام لے کر دنیا میں پھیل جاتی ہے.رسول کریم صلے اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کے زمانہ کو دیکھ لو.عرب صدیوں سے ذلیل اور مردہ چلے آرہے تھے اُن کادنیا میں کہیں غلبہ نہ تھا.اُن کی ترقی کے کوئی آثار نہ تھے.وہ دنیا سے الگ ایک گوشہ ٔ گمنامی میں پڑے ہوئے تھے.جب اللہ تعالیٰ کا کلام نازل ہوا تو بے شک وہ قرآن کریم کی مخالفت کرتے تھے.وہ اسلام کو مٹانے کی کوششیں کرتے تھے مگر ساتھ ہی اُن کے دلوں میں یہ حسرت بھی موجود تھی کہ ہر قوم نے ترقی کی.ہر قوم نے عروج حاصل کیاہر قوم نے غلبہ پایا مگر ہمیں کوئی ترقی حاصل نہیں ہوئی.پس اُن کے دلوں میں ترقی کی تڑپ پائی جاتی تھی.وہ چاہتے تھے کہ غلبہ حاصل کریں اور ان کی ذاتی خواہش تھی کہ ہماری قوم کو بھی عزت ملنی چاہیے اور اسے بھی دنیا میں غلبہ حاصل ہونا چاہیے اور اس خواہش نے اسلام لانے پر انہیں ترقی میں بڑی مدد دی.پس جب بھی کلام الٰہی نازل ہوتا ہے اسی قوم میں نازل ہوتا ہے جو مدتوں سے مرد ہ ہوتی ہے.اس زمانہ میںبھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام
Page 32
کو اللہ تعالیٰ نے ہندوستان میں مبعوث فرمایا جہاں کے رہنے والے مدتوں سے غلا می کی زندگی بسر کر رہے ہیں اور جن کے دلوں میں یہ خواہش پائی جاتی ہے کہ ہم بھی بڑھیں اور ترقی کریں.اور گو وہ لوگ احمدیت کی مخالفت کرتے ہیں جس طرح عرب کے رہنے والے اسلا م کی مخالفت کیا کرتے تھے مگر جس دن اُن کو پتہ لگا کہ احمدیت ہی اُن کی ترقی کا ذریعہ ہے اُسی دن اُن کے اندر بیداری پیدا ہو جائے گی اور وہ اس غرض کے لئے ہر قسم کی قربانی کرنے پر تیار ہو جائیں گے.وَجَعَلْنَا النَّھَارَ مَعَاشًا میں اللہ تعالیٰ نے اس طرف بھی اشارہ فرمایا ہے کہ درحقیقت زندگی کا ثبوت صرف دن سے ہی ملتا ہے رات سے نہیں ملتا.یہاں ایک عجیب لفظی لطیفہ ہے.انسان عام طور پر راحت اور آرام کے سامانوں میں اپنی زندگی بسر کرنا ہی عیش سمجھتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کو تم عیش سمجھتے ہووہ عیش نہیں بلکہ ایک نیند ہے جوتم پر مسلّط ہوتی ہے.تم سمجھتے ہو کہ کھانا پینا سیر وسیاحت کرنا.راحت و آرام کے سامانوں میں چکرلگانا انسان کے لئے عیش ہوتا ہے حالانکہ عیش کا زمانہ صر ف نبی کا زمانہ ہوتا ہے جب حقیقی کام کا وقت ہوتا ہے اور جب حقیقی عزت حاصل کرنے کا موقع ہوتا ہے.کھانا پینا اور مادی راحت و آرام کے سامانوں سے لطف اُٹھانا یہ عیش نہیں بلکہ سونا ہے.گویا جس کو تم عیش کہتے ہو وہ تمہارے سونے کا زمانہ ہے اور جس کو تم تکلیف کا زمانہ کہتے ہو وہ حقیقی معنوں میں عیش کا زمانہ ہے جس طرح دن کو انسان چلتا پھرتا ہے اور رات کو آرام کرتا ہے اسی طرح کام کا وقت عیش کا وقت کہلاتا ہے اور آرام کا وقت لیل کا وقت کہلاتا ہے دنیا میں جس چیز کو عیش سمجھا جاتا ہے وہ سکون کا زمانہ ہوتا ہے.اور جس چیز کو تکلیف سمجھا جاتا ہے وہ کام کا زمانہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ عجیب بات ہے کہ تم سکون والی چیز کا نام عیش رکھتے ہو حالانکہ عیش کا زمانہ وہ ہے جس میں انسانی طاقتیں متحرک ہوں اور اس کے لئے لَیْل کا وقت نہیں بلکہ نہار کا وقت مقرر ہے اور درحقیقت و ہی زمانہ عیش کا ہو تا ہے جب قوم میں قربانی کی روح پائی جاتی ہو.جب اُس کے تمام افراد میں بیداری نظر آتی ہو.جب اُس کے ہر فرد میں یہ احساس پایا جاتا ہو کہ جان کو قربان کر دینا اور مال کو خدا تعالیٰ کی راہ میں لٹا دینا ہی کلید کامیابی ہے.کیونکہ زندگی حرکت کا نام ہے سکون کا نام نہیں.پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کو تم عیش کہتے ہو وہ سکون ہے اور تباہی کی علامت.اور جس کو تم تکلیف کا وقت کہتے ہو وہی عیش ہے.تم سکون والی زندگی کو عیش کی زندگی قرار دیتے ہو حالانکہ وہ عیش نہیں بلکہ ایک نیند ہے جو تم پر طاری ہوتی ہے اس کے مقابلہ میں جس چیز کو تم عیش قرار دینے کے لئے تیا ر نہیں وہی حقیقی معنوں میں عیش ہے.گویا ان الفاظ کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے اُن کی ایک غلطی کا ازالہ کیا کہ عیش نام ہے حرکت کا جیسے انسان دن میں حرکت کرتا ہے.مگر تم عدمِ حرکت کا نام عیش رکھتے ہو
Page 33
حالانکہ وہ عیش نہیں بلکہ تمہارے حواس کا بطلان ہے.وَّ بَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًاۙ۰۰۱۳ اور ہم نےتمہارے اوپر سات (بلند اور) مضبوط (آسمان)بنائے ہیں.حل لغات.شِدَادًا شِدَادٌ شَدِیْدٌ کی جمع ہے اور اَلشَّدِیْدُ کے معنے ہیں اَلشُّجَاعُ وَالْبَخِیْلُ وَالْاَسَدُ وَالْقَوِیُّ وَالرَّفِیْعُ وَالْوَثِیْقُ (اقرب) یعنی شَدِیْدٌ کے معنے شجاع ؔ کے بھی ہیں.بخیل کے بھی ہیں.شیر ؔ کے بھی ہیں.قویؔ کے بھی ہے.بلندؔ کے بھی ہیں اور مضبوط ؔ کے بھی ہیں.شَدِیْدٌ کی شِدَادٌ بھی آتی ہے اور اَشِدَّاءُ بھی آتی ہے جیسا کہ قرآن کریم میں ہی اللہ تعالیٰ ایک دوسرے مقام پر صحابہؓ کی تعریف کرتے ہوئے فرماتا ہے اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ(الفتح :۳۰) یہاں سَبْعًا شِدَادًا کے معنے ہوں گے سَبْعًا رِفَاعًا یعنی سات اونچی چیزیں ہم نے پیدا کی ہیں اسی طرح قَوِیٌ کے معنےبھی ہو سکتے ہیں اور وَثِیْق کے معنے بھی ہو سکتے ہیں.گویا اس آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ ہم نے سات وہ چیزیں پیدا کی ہیں جو بلند ہیں یا ہم نے سات وہ چیزیں پیدا کی ہیں جو قوی ہیں یا ہم نے سات وہ چیزیں پیدا کی ہیں جو بندھی ہوئی ہیں اپنی جگہ سے ہلتی نہیںہیں.تفسیر.سَبْعًا شِدَادًا سے مراد سات آسمان یہ سات کیا چیزیں کیا ہیں؟ قرآن کریم میں دوسری جگہ آسمانوں کے لئے چونکہ سات کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اس لئے یہاں بھی سات سے مراد سات آسمان ہی ہوں گے اوربَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا کے معنے یہ ہوں گے کہ ہم نے تمہارے اوپر سات جسمانی اور مادی بلندیاں پیدا کی ہیں جو بڑی قوی ہیں یعنی اُن میں کوئی تزلزل واقعہ نہیں ہوتا.ایک مضبوط قانون اُن میں چلتا چلاجاتا ہے جو کسی حالت میں بھی ٹوٹتا نہیں اور اس وجہ سے نظامِ عالم میں کوئی نقص پیدا نہیں ہوتا.شِدَاد کے معنے اگر ہم رَفِیْع ؔکے لیں تو اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ ہم نے ایک ایسا وسیع اور بلند وبالا نظام تمہارے لئے قائم کیا ہے جس کا رفعت میں کوئی خاتمہ نظر نہیںآتا.اسی طرح یہاں وَثِیْق کے معنے بھی لئے جاسکتے ہیں یعنی وہ نظام جسے ہم نے قائم کیاہے اُس میں یکرنگی پائی جاتی ہے ایک قانون جس رنگ میں ظاہر ہوتا ہے اُسی رنگ میں چلتا چلا جاتا ہے.یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ یکرنگی اور نہ ٹوٹنے میں فرق ہوتا ہے.نہ ٹوٹنے میں صرف ایک چیزقائم رہتی ہے لیکن یکرنگی اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ قانون بالکل یکساں رہتا ہے اُس میں کوئی تغیر واقع نہیں ہوتا.
Page 34
لفظ شداد سے نظام سماوی کی تین خصوصیات کی طرف اشارہ دُنیا میں بعض انسان ایسے ہوئے ہیں جن میں عدم استقلال پایا جاتا ہے وہ آج کچھ کہتے ہیں تو کل کچھ کہہ دیتے ہیں ایسے لوگوں کو یکرنگ نہیں کہا جا سکتا.لیکن اللہ تعالیٰ نےجو سَبْعًا شِدَادًا بنائے ہیں اُن میں یہ تینوں خوبیاں پائی جاتی ہیں قَوِیّ کے لحاظ سے یہ معنے ہوں گے کہ ان کے اندر ثبات پایا جاتا ہے رَفِیْع کے لحاظ سے یہ معنے ہوں گے کہ ان میں وسعت اور بلندی پائی جاتی ہے اور وثیق کے لحاظ سے یہ معنےہوں گے کہ اُن میں یکرنگی پائی جاتی ہے گویابَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًاکے یہ معنے ہوئے کہ ہم نے تمہارے اوپر جوسات بلندیاں پیدا کی ہیں وہ یکرنگ بھی ہیں وہ قائم رہنے والی بھی ہیں اور اپنی ذات میں رفعت بھی رکھتی ہیں.اللہ تعالیٰ نے سَبْعًا شِدَادًا کا ذکر کرتے ہوئے یہاں اس امر کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ یہ تین خصوصیات جو نظام سماوی کی ہم نے بیان کی ہیں یہ بھی اس حقیقت کو ظاہر کر رہی ہیں کہ دُنیا کی پیدائش کا کوئی بہت بڑا مقصد ہے.جو شخض کہتا ہے کہ اس دنیا میں انسان کو پیدا کر کے بلا وجہ اور بغیر کسی مقصد کے اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ایک بہت بڑا، وسیع اور مضبوط نظام بنا دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فعل کو عبث قرار دیتا اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ گویا یہ تمام نظام نعوذ باللہ بالکل لغواور فضول ہے.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم ہمارے اس قانون کو دیکھو کہ وہ نہ ٹوٹنے والا ہے تم اس قانون کی یکرنگی کو دیکھو کہ کس طرح وہ ایک ہی رنگ میں چلتا چلا جا رہا ہے اور پھر اس نظام کی رفعت اور اس کی وسعت کا اندازہ لگاؤ.سائنسدان اس نظام کو دیکھتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں اور باجود بہت بڑی علمی ترقی کے اس نظام کی وسعت کا اندازہ لگانے سے اُن کی عقلیں قاصر ہیں.تم غور کرو اور سوچو کہ کیا یہ تمام انتظام ایک ایسی دنیا کے لئے اورپھر اس دنیا کی ایک ایسی مخلوق کے لئے کیا جا سکتا تھا جس کی پیدائش کا کوئی مقصد نہ تھا اور جس نے کچھ عرصہ کے بعدفنا ہو کر مٹی ہو جانا تھا.یہ انتظام خود اس بات کی دلیل ہے کہ انسانی پیدائش کا کوئی بہت بڑا مقصد اور مدعا ہے.نظام سماوی کا ذکر بعث بعد الموت کے ثبوت کے لئے ایک دلیل اگر اس مقصد کو تسلیم نہ کیا جائے تو یہ تمام نظام نعوذ باللہ لغوتسلیم کرنا پڑتا ہے گویا اس رنگ میں نظام سماوی کو اللہ تعالیٰ نے بعث بعد الموت کے ثبوت کے طور پر پیش کیا ہے اور بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ وسیع اور پُر حکمت نظام جاری کرنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ انسانی پیدائش صر ف اس لئے نہیں ہوئی کہ وہ چند روز کھائے اور پئے اور فنا ہو جائے بلکہ کسی بہت بڑے مقصد اور مدعا کو پورا کرنے کے لئے اس کی پیدائش ہوئی ہے.اور اگر یہاں قرآن مجید مراد لیا جائے تو مطلب یہ ہو گا کہ تم اپنی فطرت کو دیکھو اور غور کرو کہ کھانے پینے کے سوا اعلیٰ درجہ کے اخلاق کے حصول کی کتنی عظیم الشان تڑپ تمہارے دلوں میں رکھی
Page 35
گئی ہے.تمہارے اندر شوق پایا جاتا ہے کہ تم نیکی میں ترقی کرو.تمہارے اندر خواہش پائی جاتی ہے کہ تم اعلیٰ درجہ کے روحانی مدارج حاصل کرو.کیا یہ شوق اور خواہش بلا وجہ ہے اور کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو تمہاری ادنیٰ خواہشیں تھیں اُن کو پورا کرنے کے سامان تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیئے مگر جو اعلیٰ درجہ کی روحانی خواہشات تمہارے اندر رکھی گئی تھیں اُن کو پورا کرنے کا خدا نے کوئی سامان پیدا نہیں کیا.سَبْعًا شِدَادًاسے مراد سات روحانی مدارج اس صورت میں سَبْعًا شِدَادًا سے مراد وہ سات روحانی مدارج ہوں گے جن کا سورۂ مومنون میں ذکر آتا ہے اور جن کے متعلق بتایا گیا ہے کہ ایک وقت ایسا آتا ہے جب مومن ترقی کرتے کرتے ان ساتوں بلندیوں کو طے کر لیتا ہے.وَّ جَعَلْنَا سِرَاجًا وَّهَّاجًا۪ۙ۰۰۱۴ اور ہم نے ایک چمکتا ہوا سورج (بھی) بنایا ہے.حل لغات.سِرَاجٌ سِرَاجٌ کے معنے عام طور پر دیئےؔ کے ہوتے ہیں اور سُرُجٌ اس کی جمع ہے.سورج کے لئے بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے کیونکہ وہ بھی خدا کا ایک دیا ہے جو دنیا کو روشن کرنے کے لئے اُس نے بنایا ہے.وَھَّاجًا کہتے ہیں وَھَجَتِ النَّارُ والشَّمْسُ وَھْجًاوَ وَھَجَانًا: اِتَّقَدَتْ(اقرب) وَھَجَتِ النَّارُ کے معنے یہ ہوتے ہیں کہ آگ بھڑک اٹھی وَھَاج مبالغے کا صیغہ ہے یعنی اَلشَّدِیْدُالْوَھَج (اقرب) سخت گرمی والا یا سخت بھڑکنے والا.اور وَھَجٌ کے معنے اس گرمی کے بھی ہوتے ہیں جس کو دور سے محسوس کیا جائے گویا وَھَجَ کے معنے ہوئے حَرُّ الشَّمْسِ مِنْ بَعِیْدِ سور ج کی گرمی جو دور سے آرہی ہو.پس اس آیت کے معنے یہ ہوئے کہ ہم نے ایک سورج بنایا ہے جس کی صفت یہ ہے کہ وہ بڑا گرم ہَے اور اُس کی گرمی دُور دُور تک محسوس ہوتی ہے.یہاں یہ نہیں فرمایا کہ وَجَعَلْنَا السِّرَاجَ وَھَّاجًا بلکہ فرمایا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَّھَّاجًا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں تنوین تفخیمکے لے آئی ہے اگر جَعَلْنَا سِرَاجًا وَّھَّاجًا ہوتا تو اس کے معنے یہ ہوتے کہ ہم نے سورج کو وَھَّاج بنایا ہے مگر جَعَلْنَا سِرَاجًا وَّهَّاجًا کہہ کر بتا دیا کہ ہم نے ایک عظیم الشان سورج بنایا ہے جس کی صفت ذاتی یہ ہے کہ وہ وَھَّاج ہے.مفردات میں ہے اَلْوَھَجُ:حُصُوْلُ الضَّوْئِ وَالْحَرِّ مِنَ النَّارِ یعنی آگ سے روشنی حاصل کرنے اور گرمی حاصل کرنے کو وَھَّجٌ کہتے ہیں.اور جب تَوَھَّجَ الْجَوْھَرُ کہیںتو اس کے معنے ہوتےہیں تَلَاْلَأَ یعنی جو ہر چمک اُٹھا.
Page 36
اور جَعَلْنَا سِرَاجًا وَّھَّاجًا کے معنے ہیں مُضِیْئًا یعنی ہم نے سورج کو ایسابنایا ہےکہ دنیا اس سے روشنی حاصل کرتی ہے (مفردات) پس دوسرے معنے جَعَلْنَا سِرَاجًا وَّھَّاجًا کے یہ ہوئے کہ ہم نے سورج بنایا ہے جس کی ذاتی صفت یہ ہے کہ وہ بہت روشنی دینے والا ہے.تفسیر.لفظ وھاج سے سورج کی ذاتی گرمی کی طرف اشارہ سورج کی صفت وھَّاج بتاکر اُس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ سورج کی روشنی اور گرمی ذاتی ہے.چاند وھَّاج نہیں کہلا سکتا.اس لئے کہ اس میں اتّقاد نہیں ہے.آگ کی طرح جلنے والا سورج ہی ہے.سورج کے اندر خدا تعالیٰ نے ایسا انتظام کر دیا ہے کہ اس میں ریڈیم موجود ہے کششِ ثقل کے ماتحت جب اس کے ذرّے اندر کی طرف کھنچتے ہیں تو تیز روشنی اور گرمی پیدا ہوتی ہے اور ان ذرّوں کے اندر کی کشش کی وجہ سے اس سے مستقل آگ پیدا ہوتی رہتی ہے.سورج کی صفت وھَّاج بھی کتنی ظاہر ہے.کروڑوں کروڑ میل پر سورج ہے یعنی نو کروڑ میل کے قریب دنیا سے اس کا فاصلہ ہے مگراس کی گرمی جب یہاں پہنچتی ہے تو گرمیوں کے موسم میں کئی لوگ اس کو برداشت نہیں کر سکتے اور وہ مر جاتے ہیں.ابھی چند دن ہوئے لاہور کے متعلق یہ خبر آئی تھی کہ وہاں گرمی کی شدّت کی وجہ سے گھوڑے چلتے چلتے گر کر مر جاتے تھے.نیز امریکہ سے خبر آئی تھی کہ گرمی کی وجہ سے درجنوں آدمی پاگل ہو ئے اور بلند مکانوں پر سے چھلانگ مارنے پر تیار ہو گئے.گویا سورج کو اللہ تعالیٰ نے وھَّاج بنایا ہے یعنی دور دور تک اس کی گرمی پہنچتی ہے.لُغت میں اَلْوَھَجُ مِنَ النَّارِ والشَّمْسِ کے معنوں میں لکھا ہے کہ حَرُّھُمَامِنْ بَعِیْدٍیعنی سورج یا آگ کی گرمی جو بہت دور سے محسوس ہوتی ہو.گویا سِرَاجًا وَّھَّاجًا میں دو اشارے کئے گئے ہیں.اوّل یہ کہ سورج کی روشنی اور گرمی ذاتی ہے.دوسرےؔیہ کہ اس کی گرمی بہت دور سے محسوس ہوتی ہے.سورج کے جہاں اَور بہت سے فوائد ہیں وہاںاُس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ سورج کی روشنی اور اس کی تپش سے زمین کے اندر روئیدگی کا مادہ پیدا ہوتا ہے چنانچہ ہل چلانے سے محض یہ غرض نہیں ہوتی کہ زمین کو نرم کر دیا جائے بلکہ آج کل جو نئے حل بنائے گئے ہیں وہ ایسی طرز پر بنائے گئے ہیں کہ زمین کے نچلے حصہ کو اُکھاڑ کر باہر پھینک دیتے ہیں یعنی وہ ہل زمین کو صرف نرم ہی نہیں کرتے بلکہ اُوپر کی زمین کو نیچے اور نیچے کی زمین کو اُوپر کر دیتے ہیں اور اس کی غرض یہ ہوا کرتی ہے کہ زمین میں اگانے والے بعض مادے ایسے ہوتے ہیں جن کو فصل کھا جاتی ہے اور اگر پھر اُسے اُٹھا کر سورج کے سامنے نہ کیا جائے تو آئندہ فصل ناقص پیدا ہونے لگتی ہے لیکن جب نچلے حصہ کو اُلٹا کر اُوپر کر دیا جائے تو سورج کی شعائوں سے طاقت حاصل کر کے زمین کے اس نقص کی کمی پوری ہو جاتی ہے غرض سور ج کا تعلق
Page 37
فصلوںکے اُگانے میں بہت بڑا ہے اگر سورج کی گرمی اور اُس کی شعائیں نہ پہنچیں تو زمین کے بعض ایسے مادے جن سے فصلیں اُگتی ہیں بالکل ختم ہو جائیں.جَعَلْنَا سِرَاجًا وَّهَّاجًاکے الفاظ سے قیامت کی طرف لطیف اشارہ جہاں تک سِرَاجًا وَّھَّاجًا کا تعلق ہے اس میں تو میں سمجھتاہوں قیامت کی طرف اس رنگ میں اشار ہ ہے کہ ایک چیز جو اپنی ذات میں جل رہی ہے وہ آخر ایک وقت ختم ہو جائے گی اور جب وہ ختم ہو جائے گی تو نظامِ شمسی میں ضرور کوئی اہم تبدیلی رُونما ہو گی.چنانچہ علم ہئیت کے جو بڑے بڑے ماہرین ہیں وہ قیامت کے قائل ہو رہے ہیں.اس وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں سورج چھوٹا ہوتا جا رہا ہے اور اسی طرح یہ چھوٹا ہوتا چلا جائے گا یہاں تک ایک دن اس کا وجود نظامِ عالم میں بالکل بیکار ہو جائے گااور اس کے ساتھ ہی باقی تمام سیّارے فنا ہو جائیں گے.گو اس کے ساتھ ہی علم ہئیت والوں کا یہ بھی خیال ہے کہ جہاں تک گرمی کا تعلق ہے سورج کی گرمی گھٹ نہیں رہی بلکہ بڑھ رہی ہے اور جوں جوں وہ اپنے مرکز کے قریب آتا جاتا ہے اس کی گرمی تیز ہوتی چلی جاتی ہے.احادیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب قیامت آئے گی تو شدید گرمی پیدا ہو جائے گی.آیت سِرَاجًا وَّهَّاجًامیں غلبہ اسلام کی پیشگوئی رسول کریم صلے اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کے غلبہ یا قرآن کریم کے غلبہ کے مفہوم کو اگر ہم لیں تو میرے نزدیک اس میں ایک مخفی اشارہ ہجرت کی طرف معلوم ہوتا ہے.اللہ تعالیٰ ان الفاظ کے ذریعہ کفّار مکہ کو توجہ دلاتا ہے کہ اب تومحمد صلے اللہ علیہ وآلہٖ وسلم تمہارے پاس بیـٹھے ہیں اور تم کہتے ہو یہ ہمیں دق کرتے ہیں.یہ ہمارے بُتوں کو بُرا بھلا کہتے ہیں.یہ ہمیں تبلیغ کرتے ہیں.یہ ہمیں آباؤاجداد کی اتباع کرنے سے روکتے ہیں.اور جب یہ تمہیں کوئی نیک بات بتاتے اور تمہیں وعظ و نصیحت کرتے ہیںتو تم شور مچانے لگ جاتے ہو اور چاہتے ہو کہ کسی طرح ان کو اپنے شہر سے نکال دو اور اس طرح امن میں آجائو مگر تمہیں پتہ نہیں ہم نے اپنے اس رسول کو سِرَاجًا وَّھَّاجًا بنایا ہے ایک دن یہ تم سے دُور چلا جائے گا مگر پھر بھی تم اس کی گرمی سے نہیں بچو گے بلکہ برابر اس کی گرمی تمہارے پاس پہنچتی رہے گی اور اس کی روشنی تم میں سے سعید روحوں کی تاریکی کو دُور کرتی رہے گی.اگر قرآن مراد لے لو تب بھی یہ معنے ہوں گے کہ ایک دن قرآن کا مرکز تم سے دور ہو جائے گامگر تم یہ نہ سمجھوکہ دور ہو جانے کی وجہ سے تم اس کے اثر سے بچ سکو گے بلکہ پھر بھی قرآن کریم کی تعلیم کا اثر تم تک پہنچےگا اور وہ تمہیں اپنا شکار بنائے گا.آیت جَعَلْنَا سِرَاجًا وَّهَّاجًا میں اسلام کے عالمگیر ہونے کا ثبوت انبیاء کے زمانہ میں کچھ ایسا شور ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ مومنوں کے دلوںمیں کچھ اس قسم کا اخلاص پیدا کر دیتا ہے کہ انہیں تبلیغ کرنے اور دوسروں تک
Page 38
اپنی باتیں پہنچانے کے سوا چین ہی نہیں آتا.اُنہیں لاکھ گالیاں دی جائیں وہ اپنے کام سے نہیں رُکتے اور لوگوں کی ہدایت کے لئے ان کے پیچھے ہی پڑے رہتے ہیں.حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسّلام کے زمانہ میں بھی ہم مُخالفوں کے مُنہ سے یہ فقرہ سنا کرتے تھے کہ احمدی تو ہمارا پیچھا ہی نہیںچھوڑتے.تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَّهَّاجًاہم نے ایک ایسا سورج بنا دیا ہے جو وَھَّاج ہے اور جس کی گرمی اور روشنی دور دور تک جاتی ہے.دوسرےؔ رسول کریم صلے اللہ علیہ وآلہٖ وسلّم کی عالمگیر تعلیم کی طر ف بھی اس میں اشارہ ہے اور اللہ تعالیٰ یہ بیان فرماتا ہے کہ جس طرح سورج کا نور ساری دنیا میں پھیل جاتا ہے اِسی طرح محمد رسول اللہ صلے اللہ علیہ وآلہٖ وسلّم کی تعلیم ایک دن ساری دنیا میںپھیل جائے گی.تم مکّے کا رونا رو رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ مکّہ میں اسلام پھیل گیا دس بیس پچاس برس کے بعد ایک دن آئے گا جب تم دیکھو گے کہ یہ سِرَاج وَھَّاج بن جائے گا اور اس کی روشنی ساری دنیا پر چھا جائے گی.تیسرے ؔ دُور تک گرمی اور روشنی کے پھیلنے میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ رسول کریم صلے اللہ علیہ وآلہٖ وسلّم کا زمانہ ٔ افادہ زمانہ کے لحاظ سے بھی بہت ممتد ہے اور جس طرح یہ دنیوی سورج قیامت تک مادی دنیا کی ضرورتوں کو پورا کرتا رہے گا رسول کریم صلے اللہ علیہ وآلہٖ وسلّم کا افاضۂ روحانی بھی دنیا کے اختتام تک چلتا چلا جائےگا.وَّ اَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرٰتِ مَآءً ثَجَّاجًاۙ۰۰۱۵ اور ہم نے گھنے بادلوں سے کثرت سے بہنے والا پانی (بھی) اتارا ہے.حل لغات.مُعْصِرَۃٌ مُعْصِرَۃٌکے معنے ہوتے ہیں وہ بدلی جس میں نمی کی بہت زیادتی ہو اور اُس میں سے بارش کے قطرات گرتے ہوں.اَلْمُعْصِرَۃُ.اَلسَّحَابَۃُ تُعْتَصَرُ بِالْمَطَرِ.یعنی مُعصِرَۃُ اُس بدلی کو کہتے ہیں جس میں سے پانی کے قطرے ٹپکے پڑتے ہوں.پس مُعْصِرَات کے معنے ہوئے اَلسَّحَائِب تُعْتَصَرُ بِالْمَطَرَ (اقرب)وہ بادل جن میں سے پانی کی کثرت کی وجہ سے قطرے ٹپک پڑتے ہیں اور مُعْصِرَۃٌ اُس ہوا کو بھی کہتے ہیں جس کے ساتھ بگولہ آتا ہے چنانچہ اَعْصَرَتُ الرِّیحُ کے معنے ہیں جَاءَ تْ بِالْاِعْصَارِ (اقرب) ہوا کے ساتھ بگولہ آیا.لیکن محاورہ کی رو سے اَلْمُعْصِرَات: أَلسَّحَائِبُ تُعْتَصَرُ بِالْمَطَرَ کے معنوں میں ہی استعمال ہوتا ہے.گو مُعصِرَۃ کے معنے ہوا کے بھی ہو سکتے ہیں جیسا کہ بعض صحابہؓ نے کئے ہیں لیکن چونکہ عام محاورہ میں مُعصِرَۃ اُس ہوا کو کہتے ہیں جس کے ساتھ بگولہ ہواور یہ معنے یہاں پور ی طرح چسپاں نہیں ہوتے اس لئے یہاں زیادہ مناسب معنے
Page 39
حل لغات.مُعْصِرَۃٌ مُعْصِرَۃٌکے معنے ہوتے ہیں وہ بدلی جس میں نمی کی بہت زیادتی ہو اور اُس میں سے بارش کے قطرات گرتے ہوں.اَلْمُعْصِرَۃُ.اَلسَّحَابَۃُ تُعْتَصَرُ بِالْمَطَرِ.یعنی مُعصِرَۃُ اُس بدلی کو کہتے ہیں جس میں سے پانی کے قطرے ٹپکے پڑتے ہوں.پس مُعْصِرَات کے معنے ہوئے اَلسَّحَائِب تُعْتَصَرُ بِالْمَطَرَ (اقرب)وہ بادل جن میں سے پانی کی کثرت کی وجہ سے قطرے ٹپک پڑتے ہیں اور مُعْصِرَۃٌ اُس ہوا کو بھی کہتے ہیں جس کے ساتھ بگولہ آتا ہے چنانچہ اَعْصَرَتُ الرِّیحُ کے معنے ہیں جَاءَ تْ بِالْاِعْصَارِ (اقرب) ہوا کے ساتھ بگولہ آیا.لیکن محاورہ کی رو سے اَلْمُعْصِرَات: أَلسَّحَائِبُ تُعْتَصَرُ بِالْمَطَرَ کے معنوں میں ہی استعمال ہوتا ہے.گو مُعصِرَۃ کے معنے ہوا کے بھی ہو سکتے ہیں جیسا کہ بعض صحابہؓ نے کئے ہیں لیکن چونکہ عام محاورہ میں مُعصِرَۃ اُس ہوا کو کہتے ہیں جس کے ساتھ بگولہ ہواور یہ معنے یہاں پور ی طرح چسپاں نہیں ہوتے اس لئے یہاں زیادہ مناسب معنے ایسے بادل کے ہی ہوں گے جس میں پانی کی کثرت ہو اور اس میں سے پانی ٹپک رہا ہو.ہاں وضعِ لُغت کے لحاظ سے اِعْصَار کے معنے چونکہ نچوڑنے کے ہوتے ہیں اس لئے مُعْصِرَات اُن ہوائوں کو بھی کہہ سکتے ہیں جن کے تیزی سے چلنے کی وجہ سے بادلوں کے بخارات جلد مجتمع ہو کر پانی کی صورت اختیار کر لیتے ہیں.بہرحال بعض صحابہؓ نے مُعْصِرَات کے معنے ہوائوں کے کئے ہیں اور بعض نے اس کے معنے بادلوں کے کئے ہیں.اکثر مفسّرین نے ترجیح بادلوں کے معنوںکو ہی دی ہے کیونکہ لُغت کے استعمال میں یہی معنے رائج ہیں(تفسیر فتح البیان،ابن کثیر ، جامع البیان زیر آیت ھذا).ثَجَّاجًا.ثَجَّاجًا ثَجَّ سے ہے اورثَجَّ الْمَاءُ کے معنے ہوتے ہیں سَالَ(بِکَثْرَۃٍ)(اقرب) یعنی کثرت کے ساتھ پانی بہنا شروع ہوا.اور ثَجَّاج کے معنے ہیں اَلثَّجَاجُ مِنَ الْمَطَرِ: السَّیَّالُ الشَّدِیْدُ الْاِنْصِبَابِ(اقرب)یعنی ثَجَّاج اُس بارش کو کہتے ہیں جو بڑی تیزی سے برستی ہے.پس آیت کے معنے یہ ہوئے کہ ہم نے بڑی بارش والی بدلیوں میں سے جن سے پانی کی کثرت کی وجہ سے قطرات ٹپکے پڑتے ہیں ایک ایسا پانی اتارا ہے جو کثرت سے بہنے والا ہے.تفسیر.اِن آیات میں اللہ تعالیٰ نے پہلے سورج کا ذکر کیا اور پھر بدلیوں کا ذکر کر کے بتایا کہ ان دو چیزوں سے مل کر زمین تیار ہوتی ہے یعنی جب سِرَاج وَھَاج سے زمین تیار ہوتی ہے تومُعْصِرَات سے پانی برستا ہے جس سے زمین کی روئیدگیاں نشوونما حاصل کرنا شروع کر دیتی ہے.دوسرےؔان آیات میں اس امر کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ جہاں وَھَج سے زمین تیار ہوتی ہے وہاں وَھَج سے ہی بادل اُٹھتے ہیں.کیونکہ بادل کیا چیز ہیں.بادل سمندروں اور دریائوں اور نالوں وغیرہ کے پانی کے ابخرے ہیں جو سورج کی گرمی سے اُڑ کر فضاء میں جاتے اور پھر فضاء کی سردی میں سیّال بن کر زمین پر ہی واپس آجاتے ہیں.جب سورج کی گرمی ان پانیوں پر پڑتی ہے تو جس طرح آگ پر ہم پانی رکھیں تو اُس میں سے دُھؤاں اٹھنا شروع ہو جاتا ہے اور اگر زیادہ دیر تک آگ پر رکھا جائے تو تمام پانی بخارات بن کر اُڑ جاتا ہے اسی طرح سورج کی گرمی سے بخارات اُٹھتے اور آہستہ آہستہ جَوّ میں جمع ہوتے رہتے ہیں پھرہوائیں اُن کو زمین پر لا کر برسا دیتی ہے.تو ایک طرف سِرَاج وھَّاج سے زمین تیار ہوتی ہے اور دوسری طرف سِرَاج وھَّاج ہی پانی لاتا ہے گویا وہی گرمی جو انسان کے بے چین کر رہی ہوتی ہے اُس کو ٹھنڈک پہنچانے کے سامان مہیّا کر رہی ہوتی ہے.آیت اَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرٰتِ سے قیامت کی طرف اشارہ اِن آیات میں قیامت کی طرف اس رنگ
Page 40
میں اشارہ پایا جاتا ہے کہ ہر چیز کے لئے خدا نے کوئی جواب رکھا ہے.سورج آسمان پر گرم ہے زمین پر اُس کا اثر پڑتا ہے تو وہ نشوونما اور روئیدگی کے لئے تیا ر ہوتی ہے پھر وہی سورج جو ایک طرف زمین کو روئیدگی کے لئے تیار کرتا ہے اپنی گرمی سے زمین کے بخارات کو اوپر اٹھاتا ہے اور اس طرح سورج کے وَھَج کے نتیجہ میں وہ بخارات بادل بن کر زمین پر برسنا شروع ہو جاتے ہیں.سبب اور مسبّب کا یہ سلسلہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کائناتِ عالم میں جاری کیا ہوا ہے بیہودہ اور لغو نہیں ہو سکتا.ضرور ہے کہ اس کا کوئی عظیم الشان نتیجہ نکلے مگر وہ نتیجہ اس دنیا میں نہیں نکل رہااس لئے لازماً کسی اور زندگی کو ماننا پڑے گا جہاں ان عظیم الشان کاموں کا کوئی نتیجہ نکلے اور انسان کہہ سکے کہ اللہ تعالیٰ نے جس سلسلۂ کائنات کی بنیاد رکھی تھی وہ لغو نہیں تھا.آیت وَّ اَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرٰتِ میں غلبہ اسلام کی پیشگوئی قرآن مجید اور رسول کریم صلے اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کی طرف اِن آیات میں اس رنگ میں اشارہ پایا جاتا ہے کہ قرآن مجید اور محمد رسول اللہ صلے اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کی باتیں تم کو بُری لگتی ہیں تم کہتے ہو کہ انہوں نے دنیا میں آکر فساد مچا دیا.تم کہتے ہو کہ جب سے یہ ظاہر ہوا ہے جھگڑے اور لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں ایک شور ہے جو اس کی وجہ سے مچ ر ہا ہے.باپ بیٹے سے جدا ہو گیا ہے.بیٹا باپ سے جدا ہو گیا ہے.ماں لڑکی سے علیحدہ ہو گئی ہے اور لڑکی ماں سے علیحدہ ہو گئی ہے.بھائی بھائی سے علیحدہ ہو گیا ہے اور دوست دوست سے جدا ہو گیا ہے گویا تمہیں اس کے آنے کی وجہ سے ایک گرمی سی محسوس ہونے لگی ہے جیسے سورج کے نکلنے سے ایک گرمی سی محسوس ہونے لگتی ہے مگر فرماتا ہے بیشک تمہیں آج اس کی وجہ سے گرمی محسوس ہونے لگی ہے مگر یہی گرمی ایک دن تمہارے لئے رحمت کا بادل ثابت ہو گی اِس گرمی سے تمہاری اندرونی قابلیتوں کو اُبھارا جا رہا ہے.تمہارے اندر نئی قابلیتیں پیدا کی جارہی ہیں مگر تم ابھی اس کو محسوس نہیں کر سکتے بلکہ تم اس تغیّر پر تکلیف محسوس کرتے ہو جیسے ڈاکٹر جب اپریشن کرنے لگتا ہے اُس کا چاقو انسان کو چُبھتا ہے لیکن آخر وہی چاقو جس سے اُس نے تکلیف محسوس کی تھی اُس کی صحت اور آرام کا موجب بن جاتا ہے.اسی طرح فرماتا ہے بے شک محمد صلے اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کی وجہ سے تم ایک بے چینی اور تکلیف سی محسوس کر رہے ہو.مگر یہی وَھَج اور یہی گرمی اوریہی تپش اور یہی روشنی تمہاری راحت اور آرام کا موجب ہو گی.جس طرح سورج کی گرمی بادلوں کو اُٹھا کر لاتی اور زمین پر پانی کی صورت میں اُن کو برسا دیتی ہے اسی طرح ایک دن اسی وَھَج سے تمہارے دلوں میں ایمان اور عرفان کی بدلیاں اُٹھنے لگیں گی اور تمہارے دلوں سے علم و عرفان کے وہ سوتے پُھوٹ پڑیں گے جن کا پانی ساری دنیا میں پھیل جائے گا.مجھے یہاں مَآءً ثَجَّاجًا کے الفاظ سے اپنا وہ خواب یاد آگیا جو تھوڑے ہی دن ہوئے مَیں نے دیکھا تھا اور جس میں مجھے انسانی
Page 41
قلب ایک تنور کی شکل میں دکھایا گیا اور مجھے یہ نظارہ نظر آیا کہ اُس تنور میں سے اللہ تعالیٰ کے عرفان کا پانی پُھوٹنا شروع ہوا اور وہ دنیا کے کناروں تک پھیل گیا.میں نے جب اُس پانی کو پھیلتے دیکھا تو اُس وقت مَیں نے کہا یہ پانی پھیلے گا اور پھیلتا چلا جائے گا یہاں تک کہ دنیا کا ایک انچ بھی ایسا باقی نہ رہے گا جہاںخدا کے عرفان کا یہ پانی نہ پہنچے.یہی مضمون اللہ تعالیٰ نے اس جگہ بیان فرمایا ہے کہ وَّ اَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرٰتِ مَآءً ثَجَّاجًا.اس شمس روحانی کی گرمی سے تمہارے دل کی زمینیں تیار ہوں گی پھر اسی گرمی کے نتیجہ میں وہاں سے ایسے بخارات اٹھنے شروع ہوں گے جو بادلوں کی صورت اختیار کر لیں گے اور پھر وہی بادل تمہارے دلوں کی زمین پر برسیں گے اور اُن کا پانی ساری دنیا میں پھیل جائے گا.لِّنُخْرِجَ بِهٖ حَبًّا وَّ نَبَاتًاۙ۰۰۱۶وَّ جَنّٰتٍ اَلْفَافًاؕ۰۰۱۷ تا کہ اس کے ذریعہ سے ہم دانے اور سبزیاں نکالیں.اور گھنے باغ (اُگائیں).حل لغات.حَبًّا: اَلْحَبُّ وَالْحَبَّۃُ یُقَالُ فِیْ الْحِنْطَۃِ وَالشَّعِیْرِ وَنَحْرِھِمَا مِنَ الْمَطْعُوْمَاتِ یعنی گندم اور جَو اور ایسے ہی وہ تمام غلّہ جات اور اناج جن سے خوراک کاکام لیا جاتا ہے اُن کے دانوں کو حبّ کہتے ہیں.(مفردات) لسانؔ میں ہے.اَلْحَبُّ: اَلزَّرْعُ صَغِیْراً کَانَ اَوْکَبِیْرًا یعنی حبّ نباتاتی پیداوار کو کہتے ہیںخواہ چھوٹی ہو یا بڑی.نَبَاتًا: اَلنَّبْتُ وَالنَّبَاتُ مَا یَخْرُجُ مِنَ الْاَرْضِ مِنَ النَّامِیَاتِ سَوَائً کَانَ لَہٗ سَاقٌ کَالشَّجَرِ اَوْلَمْ یَکُنْ لَہٗ سَاقٌ کَالنَّجْمِ لٰکِنِ اخْتَصَّ فِیْ التَّعَارُفِ مِمَّا لَاسَاقَ لَہٗ بَلْ قَدِ اخْتَصَّ عِنْدَ الْعَامَّۃِ بِمَا یَاْکُلُہٗ الْحَیَوَانُ (مفردات) یعنی نبات زمین سے پیدا ہو کر بڑھنے والی ہر چیز پر بولتے ہیں خواہ وہ درختوں کی قسم سے ہو یا چھوٹی چھوٹی بوٹیوں کی قسم سے لیکن عرف عام میں نبات صرف اس کو کہتے ہیں جس کا تنا نہ ہو یعنی چھوٹی چھوٹی بوٹیاں ہوں.بلکہ عوام کے نزدیک صرف اُس کو نبات کہتے ہیں جس کو حیوان کھاتے ہیں.گویا حَبٌّ انسانوں کی خوراک ہوئی اور نبات حیوانوںکی خوراک.جَنَّاتٌ: جنَّاتٌ جَنَّۃٌ کی جمع ہے اور اَلْجَنَّۃُ کے معنے ہیں کُلُّ بُسْتَانٍ ذِیْ شجَرٍ یَسْتُرُ بِاَشْجَارِہِ
Page 42
الْاَرْضَ ہر وہ باغ جس میں درخت ہوں اور وہ درختوں کے ذریعے اپنی زمین کو ڈھانپ لے (مفردات ) اَلْفَافًا: اَلْفَافٌ لِفٌّ کی جمع ہے اور اَلِلّفُ کے معنے ہیں اَلصِّنْفُ مِنَ النَّاسِ مختلف طرز کے لوگوں میں سے ایک طرز کے لوگ.چنانچہ کہتے ہیںعِنْدَہٗ اَلْفَافٌ مِنَ النَّاسِکہ اس کے پاس مختلف اصناف کے لوگ بیٹھے ہیںنیز اَللِّفُّ کے معنے ہیں اَلرَّوْضَۃُ الْمُلْتَفَّۃُ النَّبَاتِ وہ باغیچہ جس کی نباتات کثیر ہونے کی وجہ سے آپس میں لپٹی ہو ئی ہو وَالبُسْتَانُ الْمُجْتَمَعُ الشَّجَرِ اور ایسے باغ کو بھی لِفّ کہتے ہیںجو گھنے درختوں والا ہو.(اقرب) پس جَنَّاتٍ اَلْفَافًا کے معنے ہوں گے ایسے گھنے باغات جو کثرت اشجار کی وجہ سے آپس میں لپٹے ہوئے ہوں.تفسیر.پانی جب آسمان سے اُترتا ہے تو اس کے بعد لِّنُخْرِجَ بِهٖ حَبًّا وَّ نَبَاتًا.وَّ جَنّٰتٍ اَلْفَافًا کا وقت آجاتا ہے یعنی اُس بارش کے نتائج پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور زمین سے دانے نکلتے ہیں.سبزیاں نکلتی ہیں.قسم قسم کی بوٹیاں پیدا ہوتی ہیں اور ایسے باغات نکلتے ہیں جو بڑے گھنے ہوتے ہیں.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب سورج نکلتا ہے تو تم جانتے ہو اُس کا ظاہری نتیجہ کیاپیدا ہوتا ہے.ظاہری نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سورج زمین تیار کرتا ہے اور اپنی روشنی کی شعائیں وہاں تک پہنچاتا ہے اور پھر اپنی گرمی کے ذریعہ زمین کا پانی کھینچ کر اوپر لے جاتا ہے گویا ایک چیز سورج دے جاتا ہے اور ایک چیز سورج لے جاتا ہے پھر جو چیز لے جاتا ہے اُسے بادلوں کی صورت میں پھر زمین کی طرف واپس کر دیتا ہے اور اس طرح سورج لوگوں کے لئے رحمت اور برکت کا سامان پیدا کر دیتا ہے چنانچہ بارش سے بڑے بڑے باغ نکلتے ہیں.سبزیاں نکلتی ہیں.کھیتی باڑی ہوتی ہے اور انسانی زندگی کے لئے جن جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ سب مہیّا ہو جاتی ہیں.اتنا بڑا کارخانہ جو خدا نے بنایا ہے کہ کروڑوں کروڑ میل پر ایک سورج بنایا ہے.کروڑوں کروڑ میل پر ایک زمین ہے.زمین میں یہ قابلیت رکھی گئی ہے کہ وہ سورج کی شعائوں کو اپنے اندر جذب کرے اور سورج میں یہ قابلیت رکھی گئی ہے کہ اُس کی گرمی پانی کو اُٹھا کر اوپر لے جائے.پھر ہوائیں چلتی ہیں جو بادلوں کو زمین پر برسا دیتی ہیں اور زمین میں سے کھیت اُگتے ہیں غلّہ پیدا ہوتا ہے.باغات تیا ر ہوتے ہیں.پھل پیدا ہوتے ہیں اور ان میں سے ایک ایک چیز انسان کے کام آتی ہے.ان میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے فوائد دیرپا نہیں ہوتے اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے فوائد دیرپا ہوتے ہیں مثلاً غلّہ ہے اِدھر غلہ پیدا ہوتا ہے اور اُدھر انسان اس کو استعمال کر نا شروع کردیتا ہے.دوسرے سال پھر غلہ بوتا ہے اور پھر استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے.لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو بار بار بونے کی ضرورت نہیں ہوتی جیسے پھلدار بوٹیاں ہیں یعنی جانوروں کے کھانے کی جھاڑیاں ہیں اُن کے پھلوںسے انسان زیادہ دیر تک فائدہ اُٹھاتا ہے اور جانور کئی سال تک اپنی
Page 43
خوراک حاصل کرتے ہیں.اور پھر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس سے بھی زیادہ عرصہ تک کام آتی ہیں مثلاًباغات ہیں کہ وہ بعض دفعہ سو سو دو دوسو تین تین سو سال تک کام دیتے چلے جاتے ہیں.اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے تم غور کرو اور سوچو کہ کیایہ سارا سلسلہ لغو اور فضول ہے.اگر تم سوچو تو تمہیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ کارخانۂ عالم کی پیدائش لغو اور فضول نہیں ہو سکتی بلکہ کوئی نہ کوئی اہم غرض ہے جس کے لئے اللہ تعالیٰ نے یہ تمام سلسلہ جاری فرمایا ہے اور کوئی نہ کوئی مقصد ہے جس کو پورا کرنے کے لئے اس قدر وسیع کارخانہ کام کر رہا ہے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ انسان کی پیدائش بالکل عبث ہے اور وہ کسی خاص مقصد کے لئے پیدا نہیں کیا گیا.اور اگر ہم ان آیات کوروحانی معنوں میں لیں تو اس کے معنے یہ بن جائیں گے کہ رسول کریم صلے اللہ علیہ وآلہٖ وسلم اور قرآن کریم دونوں سِرَاج وَھَّاج ہیں اُن کی گرمی تپش اور تیز روشنی آج تمہیں بُری لگتی ہے مگر ایک دن یہی گرمی اور تپش اور روشنی تمہارے دل کے چھپے ہوئے گند دور کرنے کے لئے بادلوں اور روشنی کا کام دے گی.سورج آخر کیا کرتا ہے یہی کہ وہ گندے پانی کو بخارات کی صورت میں اُڑاتا اور پھر ایک مصفّٰی پانی کی صورت میںاُسے زمین کی طرف لوٹا دیتا ہے اور اُس کی روشنی قسم قسم کے زہروں کو مارتی اور نئی طاقتیں بخشتی ہے.اسی طرح تمہارے پاس جو کلام الٰہی کا پانی پہلے سے موجود ہے وہ ایسا ہے جو گدلا ہو چکا ہے جس کا استعمال تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتا.بے شک تمہارے پاس ابراہیمؑ کی تعلیم بھی موجود ہے.تمہارے پاس موسیٰ ؑ کی تعلیم بھی موجود ہے.تمہارے پاس عیسیٰ ؑ کی تعلیم بھی موجود ہے.تمہارے پاس اور انبیاء کی تعلیم بھی موجود ہے مگر اُن سب تعلیموں کا پانی گدلا ہو چکا ہے.اب یہ سِرَاج وَھَّاج جس کی گرمی اور تپش اور تیز روشنی تمہیں بُری معلوم ہوتی ہے اُن چھپڑوں پرسے بخارات اُٹھائے گا اور پھر اُن بخارات کو بادلوں کی صورت میں تمہارے دلوں پر برسائے گا جس سے تمہارے دلوں کے سوتے پھوٹ نکلیں گے اور وہ ساری دنیا کو سیراب کر دیں گے اسی طرح اُس کی روشنی تمہارے دلوں کی تاریکیوں کو پھاڑ کر نورِ بصیرت تم کو بخشے گی.گویا کلام الٰہی کا وہ پانی جس کو آج تم ردّ کر رہے ہو ایک دن تمہارے دلوں سے خود بخود پھوٹنے لگے گا اورمَآءً ثَجَّاجًا بن کر ایک عالم کو سیراب کر دے گاپھر اس کے ذریعہ سے تمہارے دلوں میں سےاناج بھی نکلیں گے بوٹیاں بھی نکلیں گی اور باغات بھی نکلیں گے.گویا تمہیں کچھ ایسے فوائد حاصل ہوں گے جو قریب کے ہوں گے اور کچھ ایسے فوائد حاصل ہوں گے جو بعید کے ہوں گے یا کچھ ایسے علوم تم سے ظاہر ہوں گے جو عارف لوگوں کے کام آئیں گے جیسے علمِ تصوّف ہے یا علمِ قرآن ہے اور کچھ ایسے علوم ظاہر ہوں گے جو عوام الناس کے کام آئیں گے جیسے سائنس ہے یا جغرافیہ ہے یا حساب ہے یا ہندسہ ہے.وَّ جَنّٰتٍ اَلْفَافًا اور ایسے باغ بھی نکلیں گے جو مدتوں تک کام دیں گے جیسے علمِ تحریر میں
Page 44
مسلمانوں نے بڑی ترقی کی اور اسے دنیا میں انہوںنے پھیلا دیا.اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيْقَاتًاۙ۰۰۱۸يَّوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ یقینا یہ فیصلے کا دن ایک مقرر وقت (پر آنے والا) ہے.جس دن کہ صور میں پھونکا جائے گا.پھر تم گروہ در گروہ فَتَاْتُوْنَ اَفْوَاجًاۙ۰۰۱۹وَّ فُتِحَتِ السَّمَآءُ فَكَانَتْ اَبْوَابًاۙ۰۰۲۰ ہو کر (ہمارے حضورمیں) آؤ گے.اور آسمان کھول دیا جائے گا.یہاں تک کہ وہ دروازے (دروازے) وَّ سُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًاؕ۰۰۲۱ ہو جائے گا.اور پہاڑ (اپنی جگہ سے) چلائے جائیں گے یہاں تک کہ وہ سراب (کی مانند) ہو جائیں گے.حل لغات.یَوْمٌ اس کے معنے مطلق وقت کے ہوتے ہیںچنانچہ ایک شاعر کہتا ہے ع یَوْمَا ہُ یَوْمُ نَدًی وَیَوْمُ طَعَانٍ یعنی میرے ممدوح پر دو ہی قسم کے وقت آتے ہیں.یا تو وہ سخاوت میں مشغول ہوتا ہے یا دشمنوں کے قتل کرنے میں.اسی طرح عرب کہتے ہیں یَوْمَاہُ یَوْمُ نُعْمٍ وَیَوْمُ بُوْسٍ اَیْ الدَّھْرُ یعنی زمانہ دوحال سے خالی نہیں.یا تو انسان کے لئے نعتیں لاتا ہے یا تکالیف لاتا ہے (لسان العرب) اسی طرح سیبویہ کا قول ہے کہ عرب کہتے ہیں اَنَا الْیَوْمَ اَفْعَلُ کَذَا لَا یُرِیْدُوْنَ یَوْمًا بِعَیْنِہٖ وَلٰکِنَّھُم یُرِیْدُوْنَ الْوَقْتَ الْحَاضِرَ (لسان العرب) یعنی جب کہتے ہیں کہ میں آج کے دن اس اس طرح کروں گا تو اس سے مراد چوبیس گھنٹے کا دن نہیں ہوتا.بلکہ اس سے مراد صرف موجودہ وقت ہوتا ہے.اسی طرح اَلْیَوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ جو قرآن کریم میں آتا ہے اس سے بھی مراد معروف دن نہیں بلکہ زمانہ اور وقت مراد ہے (لسان) پھر لکھا ہے وَقَدْیُرَادُ بِالْیَوْمِ اَلْوَقْتُ مُطْلَقًا وَمِنْہُ الْحَدِیْثُ تِلْکَ اَیَّامُ الْھَرَجِ اَیْ وَقْتُہٗ (لسان) یعنی کبھی یوم سے مطلق وقت مراد ہوتا ہے.جیسے حدیث میں ہے کہ یہ فتنہ اور لڑائی کے دن ہیں.مراد یہ ہے کہ فتنہ اور لڑائی کا زمانہ ہے.اَلْفَصْل: اَلْفَصْلُ فَصَلَ کا مصدر ہے.اور فَصَلَ الشَّیْ ئَ فَصْلًا کے معنےہیں قَطَعَہٗ وَاَبَانَہٗ کسی چیز کے حصے کو کاٹ کر اس سے علیحدہ کر دیا اور اَلْفَصْلُ کے معنے ہیںاَلْحَاجِزُ بَیْنَ الشَّیْئَیْنِ دو چیزیں کے درمیان روک اور پردہ اَلْحَدُّ بَیْنَ الْاَرْضَیْنِ دوزمینوں کے درمیان حد اَلْحَقُّ مِنَ الْقَوْلِ پکی اور مضبوط بات.اَلْفَصْلُ
Page 45
اَیْضًا اَلْقَضَاءُ بَیْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ.نیز فصل کے معنے حق اور باطل کے درمیان فیصلہ ہو جانے کے بھی ہیں (اقرب ) پس یَوْمُ الْفَصْل کے معنے ہوں گے.ایسا وقت جبکہ حق اور باطل کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا.مِیْقَاتًا:مِیْقَات کے معنے ہیںاَلْوَقْتُ.مطلقاً وقت وَقِیْلَ الْوَقْتُ الْمَضْرُوْبُ للشَّیءِ کسی چیز کے لئے مقرر شدہ ہی وقت اَلْوَعْدُ الَّذِیْ جُعِلَ لَہٗ وَقْتٌ نیز اس وعدہ کو بھی مِیْقَات کہہ دیتے ہیں جس کے لئے وقت مقرر کیا جائے.اس کی جمع مَوَاقِیْت آتی ہے (اقرب) یُنْفَخُ:یُنْفَخُ نَفَخَ سے مضارع مجہول واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اور اَلنَّفْخُ کے معنے ہیں نَفْخُ الرِّیْحِ فِیْ الشَّیْءِ کسی چیز میں ہوا پھونکنا (مفردات ) پس یُنْفَخُ کے معنے ہوں گے کہ پھونکا جائے گا.اَلصُّوْرُ: صَارَا الرَّجُلُ یَصُوْرُ صَوْرًا کے معنے ہیں صَوَّتَ یعنی آواز دی.اور صُوْر اس سینگ کو کہتے ہیں جس میں پھونک مار کر اس کو بجایا جاتا ہے (اقرب) بعض نے اس کو اَلصُّوْرَۃُ کی جمع بھی قرار دیا ہے اور اَلصُّوْرَۃُ کے معنے ہیں.اَلشَّکْلُ.شکل.کُلُّ مَا یُصَوَّرُ مُشَبَّھًا بِخَلْقِ اللّٰہ مِنْ ذَوَاتِ الْاَرْوَاحِ وَغَیْرِھَا.کسی جاندار یا غیر جاندار کی تصویر اَلنَّوْعُ.قسم.الصِّفَۃُ.صفت (اقرب) پس یَوْمَ یُنْفَخُ فِیْ الصُّوْرِ کے معنے ہوں گے جبکہ صُوْر میں پھونکا جائے گا.اَفْوَاجًا:اَفْوَاجًافَوْجٌ کی جمع ہے اور فَوْج کے معنے انسانوں کی جماعت کے ہیںیا انسانوں کی وہ جماعت جو تیزی سے گزر رہی ہو (اقرب ) سُیِّرَتْ:سُیِّرَتْ سَیَّـرَ سے مونث مجہول کاصیغہ ہے اور سَیَّرہٗ کے معنے ہیں جَعَلَہٗ سَائِرًا اس کو چلایا.اور جب سَیَّرَہٗ مِنْ بَلَدِہٖ کہیں تو معنے ہوں گے اَخْرَجَہُ وَاَجْلَاہُ اس کو وطن سے جلا وطن کر دیا (اقرب ) اَلْجِبَالُ:اَلْجِبَالُ اَلْجَبَلُکی جمع ہے اور اَلْجَبَلُ کے معنے ہیں کُلُّ وَتَدٍ لِلْاَرْضِ عَظُمَ وَطَالَ زمین پر اُونچے ٹیلے کو جَبَل کہتے ہیں.خِلَافُ السَّاحِلِ ساحل کےمخالف مفہوم ادا کرنے کے لئے بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے یعنی خشکی کا علاقہ.سَیِّدُالْقَوْمِ وَعَا لِمُھُمْ نیزقوم کے سردار اور عالم کو بھی جَبَل کہتے ہیں (اقرب) پس سُیِّرَتِ الْجِبَالُ کے معنے ہوں گے (۱) جب پہاڑ چلائے جائیںگے (۲)جب قوموں کے سردار اور عالموں کو گھروں سے نکا لا جائے گا.سَرَابًا: مَاتَرَاہُ نِصْفَ النَّھَارِ مِنِ اشْتِدَادِ الْحَرِّ کَالْمَائِ یَلْصِقُ بِالْاَرْضِ (اقرب) یعنی سَرَاب اس ریتلے میدان کو کہتے ہیں جو دوپہر کے وقت سورج کی شعائوں میں پانی کی صورت میں نظر آتا ہے.کلیات میں لکھا
Page 46
ہے وَالسَّرَابُ فِیْ مَا لَا حَقِیْقَتَہٗ کہ سراب اُس کو بھی کہتے ہیں جس کی کوئی حقیقت نہ ہو.تفسیر.آسمان کے دروازے دروازےہوجانے کے معنے یَوْمَ یُنْفَخُ فِیْ الصُّوْرِ.یَوْمُ الْفَصْلِ کا بدل ہے یعنی یَوْمُ الْفَصْلِ سے کون سا یوم مراد ہے؟ یَوْمُ الْفَصْلِ سے مراد وہ دن ہے کہ یُنْفَخُ فِیْ الصُّوْرِ جس دن صورمیں پھونکا جائے گا فَتَاْتُوْنَ اَفْوَاجًا اور تم فوج در فوج آؤ گےوَّ فُتِحَتِ السَّمَآءُ اور آسمان کھولا جائے گا فَکَانَتْ اَبْوَابًا پس وہ دروازے ہی دروازے ہو جائے گا.آسمان کے دروازے ہو جانے کے معنے عام طور پرعذاب نازل ہونے کے ہوتے ہیں سوائے اس کے کہ کوئی قرینہ ایسا ہو جو ظاہر کر رہا ہو کہ وہاں عذاب مراد نہیں بلکہ کچھ اور مراد ہے.ورنہ اگر کوئی رویا میں دیکھے کہ آسمان پھٹ گیا ہے یا وہ چھید چھید ہو گیا ہے اور ساتھ کوئی قرینہ ایسانہ ہو جو بتا رہا ہو کہ یہاں عذاب مراد نہیں بلکہ کچھ اورہے تو اس سے مراد عذاب ہی ہو گا.لیکن اگر کوئی شخص دیکھے کہ آسمان مثلاً پھٹ گیا ہے اور ملائکہ خدا تعالیٰ کی تسبیحیں کر رہے اور خوشیاں منا رہے ہیں تو اس سے مراد یہ ہو گا کہ اب کسی نبی کی بعثت کا وقت ہے.بہرحال عام طور پر فتح سماء کے معنے عذاب کے ہی ہوتے ہیں اور جب سماء سے مراد ظاہری سماء ہو تو اُس وقت فُتِحَتِ السَّمَآءُ کا یہی مفہوم ہوتا ہے کہ عذاب کا وقت آ گیا ہے.قیامت کے دن پہاڑوں کی تباہی وَّ سُيِّرَتِ الْجِبَالُ.اورپہاڑ اپنی جگہ سے چلائے جائیں گے فَکَانَتْ سَرَابًا پس وہ سراب کی طرح ہو جائیںگے.سراب وہ ریتلا میدان ہوتا ہے جو دوپہر کے وقت سورج کی شعائوں کے نیچے پانی کی صورت میں نظر آتا ہے.پہاڑ چونکہ زمین میں سے نکلتے ہیں اور ریت بھی زمین سے ہی پیدا ہوتی ہے اس لئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک وقت زمین پر ایسی تباہی آئے گی کہ پہاڑ گر جائیں گے اور چونکہ پہاڑ اَوْتَادُ الْاَرْضِ ہوتے ہیں اس لئے جب اَوْتَاد گر جائیں گے تو ساری زمین تباہ ہو جائے گی.معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن پھر زمین میں ایسی گرمی پیدا ہو گی جو نہایت ہی شدید ہو گی اور وہ ایسی تیز ہو گی کہ بجائے اس کے کہ اُس گرمی سے پہاڑ بنیں موجودہ پہاڑ بھی اس کی وجہ سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے اور باقی زمین بھی تباہ ہو جائے گی.یوم الفصل سے مراد قیامت یا غلبہ اسلام یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اِنَّ یَوْمَ الْفَصْلِ کَانَ مِیْقَاتًا اور میں نے بتا یا ہے کہ یَوْمُ الْفَصْل سے مراد قیامت بھی ہے اوریَوْمُ الْفَصْل سے قرآن کریم یا رسول کریم صلے اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کے غلبہ کا ظہور بھی مراد ہے اور درحقیقت یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں گو نام مختلف رکھ دیا گیا ہے.چاہے نبوت کے کمالات کا ظہور ہو یا کلام الٰہی کا ظہور ہو بات ایک ہی ہے.بہرحال اِنَّ یَوْمَ الْفَصْلِ کے معنے ہوئے
Page 47
جدائی کا دن اور اِنَّ یَوْمَ الْفَصْلِ کَانَ مِیْقَاتًا کے معنے ہوئے یَوْمُ الْفَصل کا ایک وقت مقرر ہے اس یَوْمُ الْفَصْل سے جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں غلبۂ اسلام بھی مراد ہے مگر اس میں ایک اور امر کی طرف بھی اشارہ ہے اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کفّار مکّہ کو مخاطب کر کے فرماتا ہے جس طرح محمد صلے اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کو تمہارے ظلموں کی وجہ سے تم سے جدا ہو نا پڑا ہے اسی طرح خدا ایک دن محمد صلے اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کو غلبہ دے کر تم کو بھی جُد ا کر دے گا اور وہ دن تمہارے لئے یَوْمُ الْفَصْل ہو گا.چنانچہ اِسی کی طرف سورۂ توبہ میں اشارہ کیا گیاہے.جو درحقیقت سورۂ انفال کا دوسرا باب ہے.یہ سورۃ شروع ہی اس طرح ہوتی ہے کہ بَرَآءَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖۤ اِلَى الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ.فَسِيْحُوْا فِي الْاَرْضِ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّ اعْلَمُوْۤا اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللّٰهِ١ۙ وَ اَنَّ اللّٰهَ مُخْزِي الْكٰفِرِيْنَ.وَ اَذَانٌ مِّنَ اللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖۤ اِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْاَكْبَرِ اَنَّ اللّٰهَ بَرِيْٓءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ١ۙ۬ وَ رَسُوْلُهٗ١ؕ فَاِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ١ۚ وَ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوْۤا اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللّٰهِ١ؕ وَ بَشِّرِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ.اِلَّا الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوْكُمْ شَيْـًٔا وَّ لَمْ يُظَاهِرُوْا عَلَيْكُمْ اَحَدًا فَاَتِمُّوْۤا اِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ اِلٰى مُدَّتِهِمْ١ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ.فَاِذَا انْسَلَخَ الْاَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ وَ خُذُوْهُمْ وَ احْصُرُوْهُمْ وَ اقْعُدُوْا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ١ۚ فَاِنْ تَابُوْا وَ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَخَلُّوْا سَبِيْلَهُمْ١ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.(آیات :۱ تا ۵) سورۃ نبأ کے موعود یوم الفصل کا ذکر سورۃ توبہ میں اس سورۃ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے کہ چار مہینے کفّار کو یہاں رہنے کی اجازت ہے.جب چار مہینے گذر جائیں تو پھر کفّار یہاں سے چلے جائیں.یہ وہ یَوْمُ الْفَصْل ہے جو کفّار پر آیا اور جس کا فتح مکّہ کے بعد اعلان کیا گیا گویا فتح مکّہ کا نتیجہ ہی یَوْمُ الْفَصْل تھا.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ یَوْمَ اِنَّ یَوْمَ الْفَصْلِ کَانَ مِیْقَاتًا وہ موعود دن تم پر آنےوالا ہے جب تم کو اپنے گھروں اور وطن سے جُدا ہونا پڑے گا.یعنی ایک دن ایسا آنیوالا ہے جب مسلمان نہ صرف غالب آجائیںگے بلکہ وہ اتنے غالب ہوںگے کہ مشرکوں کووہ کھلے بندوں یہ سُنا دیں گے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ ہمارا تمہارا کوئی جوڑ نہیں.ایسا غلبہ عام حالات میں نہیں ہوتا بلکہ غیر معمولی حالات میں ہی ہو سکتا ہے.سپینؔ پر مسلمانوں کو ایک لمبے عرصہ تک غلبہ حاصل رہامگر باوجود غلبہ کے وہ عیسائیوں کو سپین میں سے نکال نہ سکے.اسی طرح اور کئی ممالک ایسے ہیں جہاں مسلمان حکمران ہوئے مگر وہ غیر مذاہب والوں کے اپنے ملکوں سے نکال نہیں سکے.ہندوستان میں ہی مسلمانوں کی ایک لمبے عرصہ تک حکومت رہی مگر وہ ہندوئوں کو نہ نکال سکے.آجکل ہندوستان میں ہندو بہت طاقتور ہیں مگر وہ مسلمانوں کو نہیں نکال سکتے بلکہ انگریز جن کے ماتحت ہندوستانی ہیں وہ بھی ہندستانیوں سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم ہندوستان سے
Page 48
چلے جائو.لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ یَوْمَ الْفَصْلِ کَانَ مِیْقَاتًا.ایک ایسے عظیم الشان غلبے کا دن آنےوالا ہے جو یَوْمُ الْفَصْل ہو گا.وہ نہ صرف عام فیصلے کا دن ہو گا بلکہ یَوْمُ الْفَصْل ہو گا یعنی وہ فَصْلٌ بَیْنَ الْحَقِّ وَ الْبَاطِلِ ہی نہ ہوگا بلکہ فَصْلٌ بَیْنَ الْمُشْرِکِیْنَ وَالْمُؤْمِنِیْنَ بھی ہوگا.چنانچہ سورۂ بَرَآءَ ۃٌ میں اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہےبَرَآءَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖۤ اِلَى الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ.مشرکوں میں سے جن سے عہد کیا گیا تھا کہ ایک دن ایسا آنےوالا ہے جب مسلمانوں کو تم پر غلبہ حاصل ہو جائے گاتُم اُن کے مقابلہ میں بالکل ذلیل اور حقیر ہو جائو گے تمہیں وہ مکّہ میں بھی نہیں رہنے دیں گے بلکہ کہیں گے کہ تم یہاں سے چلے جائو اور اُس وقت تم ذلّت اور رسوائی کی حالت میں اِدھر اُدھر دوڑ رہے ہو گے.اُن مشرکوں کو کہو کہ اب اُس پیشگوئی کے پورا ہونے کا وقت آگیا ہے گویا اس صورت میںبَرَآءَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖۤ اِلَى الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ کے یہ معنے ہوںگے کہ اللہ کی طرف سے برأت ہے اور اس کے رسول کی طرف سے بھی برأت ہے اُن مشرکین کے مقابلہ میں جن سے تم نے عہد کیا تھا.اِن معنوں کے رُو سے میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہاں صلح حدیبیہ والے معاہدے کا ذکر آتا ہے بلکہ ان معنوں کے رُو سے عَاھَدْتُّمْ سے مراد وہ معاہدہ ہو گا جس کا سورۂ نبا میں ذکر آتا ہے یعنی سورۂ نبا میں تم سے کہا گیا تھا کہ اے کافرو! ایک دن ایسا آنیوالا ہے جب تم مکّہ میں سے نکال دیئے جائو گے.یہی وہ عہد جس کا سورۂ توبہ میں عَاھَدْتُّمْ کے الفاظ میں ذکر آتا ہے.اس پیشگوئی کو عہد کے نام سے اس لئے پکارا گیا ہے کہ بنی جب کوئی ایسی پیشگوئی کرتا ہے جس کا کفّار پر بھی اثرپڑتا ہو تو مومنوں کو ہی یہ شوق نہیں ہوتا کہ وہ اُس پیشگوئی کو پورا ہوتا دیکھیں بلکہ اگر وہ پیشگوئی کسی وجہ سے پوری نہ ہو تو دشمن بھی مطالبہ کرتا ہے کہ وہ پیشگوئی کیوں پوری نہیں ہوئی اس لئے وہ عہد کا رنگ اختیار کرلیتی ہے.پس عَاھَدْتُّمْ میں سورۂ نبا والی پیشگوئی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور فرمایا گیا ہے کہ اب خدا اور اس کے رسول کی برأت ہوگئی یعنی اب تم یہ الزام نہیں دے سکتے کہ وہ پیشگوئی پوری نہیں ہوئی بلکہ ہم نے جو تم سے کہا تھا کہ ایک دن ایسا آنیوالا ہے جب مسلمانوں کو تم پر غلبہ حاصل ہو جائے گا اور تم مکّہ میں نہیں ٹھہر سکو گے ہماری وہ بات پوری ہو گئی ہے.فَسِيْحُوْا فِي الْاَرْضِ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ ہم نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ اسلام کو غلبہ حاصل ہو جائے گا اور ہم نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ ایک دن تمہیں اپنے ملک سے نکال دیا جائے گا اب ہم نے اپنے اس عہد کو پورا کر دیا ہے مگر چونکہ غلبۂ اسلام دیکھنے کے لئے تمہارا ٹھہرنا ضروری ہے اور پیشگوئی کے پورا ہونے کے لئے تمہاری وطن سے جدائی ضروری ہے اس لئے ہم نے تمہارے رہنے کے لئےچار مہینے مقرر کر دیئے ہیں تاکہ تم اس عرصہ میں سارے عرب
Page 49
میں پھرو اور دیکھو کہ خدا کی باتیں کس طرح پوری ہوئیںوَّ اعْلَمُوْۤا اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللّٰهِاور تم دیکھ لو کہ خدا کا حکم جو اسلام کے غلبہ کے متعلق تھا وہ پورا ہو گیا ہے یا نہیںوَاَنَّ اللّٰہَ مُخْزِی الْکٰفِرِیْنَ اور اللہ کافروں کو ذلیل کرنے والا ہے وَ اَذَانٌ مِّنَ اللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖۤ اِلَى النَّاسِ اور اعلان ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے یَوْمَ الْحَجِّ الْاَکْبَرِ حج اکبر کے دن.یعنی خدا نے اس اعلان کے لئے حجِ اکبر کے دن کومخصوص کیا ہے تا کہ سارے عرب کو یہ اعلان سنایا جاسکے.یُوں اگر اعلان کر دیا جاتا تو چار ماہ میں بھی سارے عرب میں نہ پہنچ سکتا.اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس اعلان کے لئے حجِ اکبر کا دن تجویز فرما دیا.اس فیصلہ سے فَسِیْحُوْا فِیْ الْاَرْضِ اَرْبَعَۃَ اَشْھُرٍ کا حکم بھی پورا ہو گیا.کیونکہ حج کے موقع پر عرب کے ہر علاقہ سے لوگ آتے ہیں پس اللہ تعالیٰ نے حج کے دن کا انتخاب اسی حکمت کے ماتحت فرمایاکہ جب لوگ حج سے واپس جائیں گےتو اس اعلان کے ساتھ ہی وہ اپنی آنکھوںسے یہ بھی دیکھتے چلے جائیں گےکہ اسلام کا ہر علاقہ میں غلبہ ہو گیا ہے.درحقیقت یہ بھی اسلامی تعلیم میں رحم کے غلبے کاثبوت ہے کہ اعلان اُس وقت کیا گیا جب سارے لوگ موجود تھے اور اعلان یہ کیا گیا کہ اَنَّ اللّٰهَ بَرِيْٓءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ اللہ مشرکوں کے الزام سے پاک ہے.وہ اس عظیم الشان غلبہ کے بعد جس کا ظہور انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے اللہ تعالیٰ پر یہ الزام نہیںلگا سکتے کہ سورۃ نباء میں جو پیشگوئی کی گئی تھی وہ پوری نہیں ہوئی وَرَسُوْلُہٗ اور رسول بھی اِس الزام سے بری ہے فَاِنْ تُبْتُمْ فَھُوَ خَیْرٌ لَّکُمْ اگر تم توبہ کرو تو تمہارے لئے بہترہے وَ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوْۤا اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللّٰهِ١ؕ وَ بَشِّرِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ.اور اگر تم پھر جائو تو یاد رکھو جب تم پہلے ہمیں عاجز نہیں کرسکے تو آئندہ کس طرح کرسکو گے.اس کے بعد فرماتا ہے اِلَّا الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوْكُمْ شَيْـًٔا وَّ لَمْ يُظَاهِرُوْا عَلَيْكُمْ اَحَدًا فَاَتِمُّوْۤا اِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ اِلٰى مُدَّتِهِمْ١ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ سوائے ان لوگوں کے جن سے مشرکوں میں سے تم نے عہد کیا ہے پھر انہوں نے تم سے معاہدہ میں خلاف ورزی نہیں کی اور تمہارے خلاف کسی دشمن کی مدد نہیں کی پس اُن سے جو عہد کیا ہے اُسے مقررہ معیاد تک نبا ہو اللہ تعالیٰ متقیوں کو پسند فرماتا ہے.یہ دلیل ہے میرے اُن معنوں کے درست ہونے کی جو ابھی میں نے بیان کئے ہیں.وہاں خدا تعالیٰ نے فرمایا تھاکہ بَرَآءَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖۤ اِلَى الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ.فَسِيْحُوْا فِي الْاَرْضِ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّ اعْلَمُوْۤا اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللّٰهِ١ۙ وَ اَنَّ اللّٰهَ مُخْزِي الْكٰفِرِيْنَگویا عہد کے باجود اللہ تعالیٰ نے مشرکوں سے کہا تھا کہ مکّہ میںسے نکل جائو مگر یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن مشرکین سے تم نے معاہدہ کیا ہواہے اورانہوں نے اِس معاہدہ کو توڑا نہیں اُن کے معاہدہ کو دیانتداری کے ساتھ پورا کرو اس سے صاف پتہ لگتا ہے کہ وہ معاہدہ اَور ہے اور یہ معاہدہ اَور ہے.اِلَّا الَّذِيْنَ
Page 50
عٰهَدْتُّمْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ میں جس معاہدے کا ذکر ہے وہ دُنیوی معاہد ہ ہے اور پہلی آیت میں جس معاہدے کا ذکر آتا ہے اس سے الہامی معاہدہ مراد ہے یعنی وہ معاہدہ جس کا الہامی طور پر ذکر کیا گیا تھا اور جس کے متعلق کہا گیا تھا کہ اگر وہ جھوٹا نکلے تو تمہارا حق ہے کہ گرفت کرو اور کہو کہ تمہاری یہ بات کیوں پوری نہیں ہوئی.ایک عہد یکطرفہ ہوتا ہے جس میں انسان خود اپنے نفس سے کوئی عہد کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مَیں ایسا کرو ں گا.اُس کے متعلق کوئی دوسرا شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم نے ایسا کیوں نہیں کیا.لیکن وہ معاہدہ جو فریقین میں ہو یا وہ وعدہ جو دو جماعتوں سے تعلّق رکھتا ہو اُس میں دوسرے کو پکڑنے اور گرفت کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے اور اگر وہ بات پوری نہ ہوتو دوسرا کہہ سکتا ہے کہ تم تو کہتے تھے فلاں بات اس طرح ہو گی مگر پھر وہ اُس طرح ہوئی نہیں.اس قسم کے معاہدات میں پیشگوئیاں بھی شامل ہیں کیونکہ اُن کے متعلق بھی کفاّر یہ مطالبہ کر سکتے ہیں کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھیں تو پھر وہ پوری کیوں نہ ہوئیں.پس ایک ہی رکوع میں دوجگہ عٰهَدْتُّمْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ کے الفاظ استعمال کرنا اور ایک جگہ تو یہ کہنا کہ جن مشرکوں سے یہ عہد تھا اُن کوچار ماہ کا نوٹس دے کر مکّہ سے نکال دو اور دوسروں کے متعلق یہ کہنا کہ اُن سے جو معاہدہ ہو چکا ہے اُس کو پورا کرو بتا رہا ہے کہ پہلے روحانی معاہدے کا ذکر تھا اور اب جسمانی معاہدے کا ذکر ہے.اس جسمانی معاہدہ کے متعلق اللہ تعالیٰ یہ ہدایت دیتا ہے کہ تم نے اِسے نہیں توڑنا ہاں اگرکفّار توڑ دیں تو اَور بات ہے.لیکن اگر اُن کی طرف سے نقضِ عہد نہ ہو تو پھر معاہدہ کی جو بھی معیاد ہے اُس معیاد تک تمہاری طرف سے یہ پوری کوشش ہونی چاہیے کہ اُس کا احترام کرو.چنانچہ فرماتا ہےفَاَتِمُّوْۤا اِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ اِلٰى مُدَّتِهِمْ اس میں چار ماہ کی کوئی شرط نہیں اگر دو سال کا معاہدہ ہے تو دو سال پورے کرو اور اگر چار سال کا معاہدہ ہے تو چار سال پورے کرو اور اگر چھ سال کا معاہدہ ہے تو چھ سال پورے کرو.غرض جتنی مدّت مقرر ہے اُس مدّت تک معاہدے کو پورا کرو.غرض اِنَّ یَوْمَ الْفَصْلِ کَانَ مِیْقَاتًامیں قرآن اور رسول کریم صلے اللہ علیہ وآلہٖ وسلّم کے غلبہ کی پیشگوئی کی گئی ہے اور کفّار کو بتایا گیا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا جب نہ صرف مسلمانوں کو تم پر غلبہ حاصل ہو جائے گا بلکہ اس غلبہ کے ساتھ ہی تم کو مکّہ سے نکال دیا جائے گا.اب اگلی آیات میں اس غلبہ کا وقت بتایا گیا ہے فرماتا ہے يَّوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ فَتَاْتُوْنَ اَفْوَاجًا جس دن صور پھونکا جائے گااور تم فوج در فوج کی صورت میں آئو گے وَّ فُتِحَتِ السَّمَآءُاور آسمان کھول دیا جائے گا.فوج در فوج اور گروہ در گروہ لوگوں کےآنےکی خبر اُس وقت پوری ہوئی جب مکّہ فتح ہوا بلکہ صلح حدیبیہ کے بعد ہی سارے عرب میں ایک ہلچل سی مچ گئی تھی اور فتح مکّہ کی جنگ درحقیقت اسی ہلچل کا نتیجہ تھی کیونکہ عربوں میں یہ احساس پیدا ہونا شروع ہو گیا تھا کہ اب اُن کے لئے دو ہی صورتیں ہیں یا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کے ساتھ مل جائیں
Page 51
اَور یا مکّہ والوں کے ساتھ مل جائیں چنانچہ کچھ لوگ ادھر آگئے اور کچھ لوگ اُدھر چلے گئے وَّ فُتِحَتِ السَّمَآءُاور آسمان پر سے عذاب نازل ہونا شروع ہو جائے گا.نفخ صور سے مراد نفخِ صور سے اگر صلح حدیبیہ مرا د لے لو تو اِن آیات کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک ایسا واقعہ رونما ہو گا جس سے عرب قبائل میںبے چینی پیدا ہو جائے گی اور اُن کے دلوںمیں یہ خیال پیدا ہونا شروع ہو جائے گا کہ اب اُنہیں کُھلے طور پریااسلام میں شامل ہونا چاہیے.یا مکہ والوں کے ساتھ مل جانا چاہیے چنانچہ صلح حدیبیہ کے وقت سے لوگوں میں یہ احسان پیدا ہونا شروع ہو گیا کہ اب معاملہ اس قدر بڑھ چکا ہے کہ ہم یا محمد صلے اللہ علیہ وآلہٖ وسلّم کے ساتھ رہ کر بچ سکتے ہیں یا مکّہ والوں کے ساتھ رہ کر بچ سکتے ہیں چنانچہ اسی خیال کے زیرِ اثر کچھ قبائل رسول کریم صلے اللہ علیہ وآلہٖ وسلّم کے ساتھ مل گئے اور کچھ قبائل کفّار کے ساتھ مل گئے گویا یَوْمُ الْفَصْل کی بنیاد صلح حدیبیہ نے رکھ دی.وَ فُتِحَتِ السَّمَآءُ اور آسمان کھولا جائے گافَکَانَتْ اَبْوَابًا اور وہ دروازے دروازے بن جائے گا.اِن معنوں کے لحاظ سے فَکَانَتْ اَبْوَابًا کا یہ مفہوم ہو گا کہ آسمان سے کفّار پر عذاب نازل ہوں گے اور مومنوں پر اُس کی رحمت کی بارش برسے گی گویا آسمان ابواب ابواب ہو جائے گا.کچھ دروازے ایسے ہوںگے جن سے خیر نازل ہو گی اور کچھ دروازے ایسے ہوں گے جن سے عذاب نازل ہو گا ہی پہلے بھی مسلمانوں پر آسمان سے خیر نازل ہوئی تھی مگر وہ ایسی ہی تھی جیسے چھیدو ں میں سے کوئی چیز گرائی جاتی ہے لیکن صلح حدیبیہ کے بعد یہ خبر اس طرح مسلمانوں پر گرنے لگی جیسے بڑے بڑے دروازوںمیں سے کوئی چیز گرتی ہے.اسی طرح کفّار پر کثرت سے عذاب آنے شروع ہو گئے.گویا آسمان سے رحمت کے سامان بھی نازل ہونے لگ گئے اور عذاب کے سامان بھی نازل ہونے شروع ہو گئے.سُيِّرَتِ الْجِبَالُ سے مراد صنادید عرب کی تباہی وَ سُيِّرَتِ الْجِبَالُ.جِبَال کے معنے سردارانِ قوم کے بھی ہوتے ہیں.پس سُیِّرَتِ الْجِبَالُ کے یہ معنے ہوئے کہ بڑے بڑے صنادید عرب اور وہ بڑے بڑے سردار جن پر اہلِ عرب کو ناز ہے اپنے گھروں سے نکالے جائیں گے.فَکَانَتْ سَرَابًا اور وہ سراب کی طرح ہو جائیں گے یعنی ثابت ہو جائے گاکہ اُن میں کوئی ایسا لیڈر نہیں جو قوم کی صحیح راہنمائی کرنے والا ہو.بلکہ سب کے سب لیڈر محمد رسول اللہ صلے اللہ علیہ وآلہٖ وسلّم کے مقابلہ میں ناکام رہیں گے.سَرَابًا کا لفظ جو اس جگہ رکھا گیا ہے اس میں حکمت یہ ہے کہ سَرَاب نصف النہار میں نظر آیا کرتا ہے.اس لفظ میں اس امرکی طرف بھی اشارہ تھا کہ جب محمد صلے اللہ علیہ وآلہٖ وسلّم کا سورج نصف النہار پر پہنچے گا اور اُس کی چمک لوگوں کی آنکھوں کو خیر ہ کر دے گی اُس وقت اُنہیں معلوم ہو جائے گا کہ رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلّم کے مقابلہ میں اُن کے لیڈر کیسے ناکام اور کس قدر عقل وخرد سے عاری ہیں.چنانچہ
Page 52
صلح حدیبیہ کے بعد ہی اسلام کی اس فتح کے آثار ظاہر ہونے شروع ہوگئے اور فتح مکّہ نے اس کو تکمیل تک پہنچا دیا.پس فرماتا ہے اُس وقت لوگوں پر یہ ثابت ہو جائے گاکہ ان کے سارے لیڈ ر محمد رسول اللہ صلے اللہ علیہ وآلہٖ وسلّم کے مقابلہ میں ایک سراب کی حیثیت رکھتے ہیں.وہ قوم کو تباہ کرنے والے اور اُسے ذلّت کے گڑھوں میں گرانے والے ہیں.اُس کو ترقی تک پہنچانے کی اُن میں کوئی قابلیت نہیں چنانچہ ایسا ہی ہوا.اِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا۪ۙ۰۰۲۲لِّلطَّاغِيْنَ مَاٰبًاۙ۰۰۲۳ یقیناً جہنم ایک راستہ ہے (مگر مذکورہ بالا) سرکشوں کے لئے وہ ٹھہرنے کی جگہ (بھی) ہے.حل لغات.جَھَنَّمکہتے ہیں بِئْرٌ جَہَنَّمٌ اور مراد ہوتی ہے بَعِیْدَۃُ الْقَعْرِ گہری تہ والا کنواں (لسان)لسانؔ کے مصنف کہتے ہیں وَبِہٖ سُمِّیَ جَہَنَّمُ لِبُعْدِ قَعْرِھَا کہ جہنم کو اس لئے جہنم کہا جاتا ہے کہ اس کی تہہ گہر ی ہو گی.مِرْصَادًا کے معنے ہیں اَلْمَکَانُ یُرْصَدُ فِیْہِ الْعَدُوُّ وہ جگہ جہاں دشمن کی انتظار کی جاتی ہے جس کو اُردو میں گھات کہتے ہیں.نیز مِرْصَادًا کے معنے اَلطَّرِیْقُ کے بھی ہیں یعنی راستہ (اقرب ) مَاٰبٌ مَاٰب اٰبَ کا مصدر بھی ہے اور اسم زمان اور مکان بھی.اٰبَ مَابًا کے معنےہیں رَجَعَ لوٹا (اقرب) اور الماٰب کے معنے ہیں اَلْمَرْجَعُ وَالْمُنْقَلَبُ لوٹنے کی جگہ.(اقرب ) صاحب مفردات کہتے اَلْاَوْبُ ضَرْبٌ مِنَ الرُّجُوْعِ وَذَالِکَ اَنَّ الْاَوْبَ لَا یُقَالُ اِلَّا فِیْ الْحَیَوانِ الَّذِیْ لَہٗ اِرَاْدَ ۃٌ والرُّجُوْعُ یُقَالُ فِیْہِ وَفِیْ غَیْرِہٖ (مفردات)یعنی عربی زبان میں اردو زبان کے لفظ ’’لوٹنے‘‘کا مفہوم ادا کرنے کے لئے دولفظ آتے ہیں (۱) رُجُوْعٌ (۲) لیکن اَوْبٌ رُجُوْعٌ سے خاص ہے اس لئے کہ اَوْبٌ اس کے لوٹنے کو کہیں گے جو ذی ارادہ ہو اور رجوع ذو ارادہ اور غیر ذی ارادہ ہر دو کے لوٹنے کو کہتے ہیں.تفسیر.جہنم کے گھات میں ہونے سے مراد قتادہ کہتے ہیں کہ مراد یہ ہے کہ جہنم گھات میں رہتی ہے جو اُس پر سے گزرتا ہے اگر اُس کے پاس جواز کا پروانہ ہو تو اُسے گزرنے دیتی ہے ورنہ اُسے وہیں گرا لیتی ہے ( ابن کثیر زیر آیت ھذا) گویا انہوں نے اس کے معنوں میں جسرِ صراط کی طرف اشار ہ کیا ہے لیکن اگر اِنَّ جَھَنَّمَ کَانَتْ مِرْصَادًا سے وہی جہنم مراد لیا جائے جو اگلے جہان میں ہو گا تو ہمیں کہنا پڑے گا کہ اس کا سِلسلہ اسی دنیا سے
Page 53
شروع ہو جاتا ہے اِسی کی طرف یہ حدیث اشارہ کرتی ہے اِنَّ الشَّیْطٰنَ یَجْرِیْ مِنَ الْاِنْسَانِ مَجْرَی الدَّمِ (صحیح بخاری کتاب الصوم باب زیارۃ المرأۃزوجہا فی اعتکافہٖ )کہ شیطان انسان کے مجری الدم میں چلتا ہے.گویا شیطانی تحریکیں دنیا میں اس قدر ہوتی ہیںکہ انسان اگر ذرا بھی غافل ہوتو وہ نفس پر غالب آجاتی ہیں.مگر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ لِلطّٰغِیْنَ مَاٰبًا یعنی یہ سرکشوںکے ٹھہرنے کی جگہ ہے.اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ فرمایا ہےاِنَّهٗ لَيْسَ لَهٗ سُلْطٰنٌ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ.اِنَّمَا سُلْطٰنُهٗ عَلَى الَّذِيْنَ يَتَوَلَّوْنَهٗ وَ الَّذِيْنَ هُمْ بِهٖ مُشْرِكُوْنَ( النّحل:۱۰۰،۱۰۱) کہ شیطان کو مومنوں پر اور خدا تعالیٰ پر توکل رکھنے والوں پرغلبہ حاصل نہیں ہو سکتا.اُس کا غلبہ اُنہی لوگوں پر ہوتا ہے جو خودشیطان سے دوستی رکھتے ہیںاور اسکی محبت کا دم بھرتے اور شرک کرتے ہیں.لِلطّٰغِیْنَ مَاٰبًا میں بھی اسی طرف اشارہ کیا گیاہے گویا اِنَّ جَھَنَّمَ کَانَتْ مِرْصَادًاکے مضمون میں وہ حدیث آگئی جس میں رسول کریم صلے اللہ علیہ وآلہٖ وسلّم نے یہ فرمایا ہے کہ شیطان انسان کے مَجْرَی الدَّم میں چلتا ہے اور لِلطّٰغِیْنَ مَاٰبًا نے بتا دیا ہے کہ گو جہنّم کا حملہ مومن و کافر سب پر ہوتا ہے کسی پر کسی رنگ میں اور کسی پر کسی رنگ میں.لیکن جہنّم ٹھکانہ کے طور پر صرف طاغین کے لئے ہے.خدا تعالیٰ تک پہنچنے کے لئے جہنم پر سے گزرنا ضروری ہے دوسری آیات سے بھی اس مضمون کی تصدیق ہوتی ہے کہ شیطان کو کفّار پر ہی غلبہ ملتا ہے مومنوں پر اُسے غلبہ حاصل نہی ہوتا.غرض جہنّم کو راستہ قرار دیا جائے یا گھات دونوں صورتوں میں اس کے یہ معنے ہیں کہ انسان کو خدا تعالیٰ تک پہنچانے کے لئے جہنّم بھی ایک ضروری شے ہے.جب تک انسان اپنے لئے جہنم یعنی تکلیف کا راستہ قبول نہ کرے خدا تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتا.اور اگر گنہ کر چکا ہو تو پھر بطور سزا کے اس تکلیف کے راستہ پر ایک عرصہ تک چلنا پڑتا ہے خواہ اسی دنیا میں یا اگلے جہان میں.اس کے بعد لقاء الٰہی نصیب ہوتا ہے.واللہ اعلم بالصواب.لِلطّٰغِیْنَ مَاٰبًا کا حال ہے یعنی اِنَّ جَہَنَّمَ کَانَتْ مِرْصَادًا وَمَاٰبًا حَالَ کَوْنِھَا لِلطّٰغِیْنَ یا یہ جملہ مِرْصَاد کی صفت بھی ہو سکتا ہے.لّٰبِثِيْنَ فِيْهَاۤ اَحْقَابًاۚ۰۰۲۴ در آنحالیکہ وہ برسوں اس میں رہتے چلے جائیں گے.حل لغات.اَحْقَابًا اَحْقَاب حُقْبٌ کی جمع ہے اور حُقْبٌ کے معنے ہیں ثَمَانُوْنَ سَنَۃً اسّی سال کا
Page 54
عرصہ.وَیُقَالُ اَکْثَرَ مِنْ ذَالِکَ اور بعض نے کہا ہےکہ اسّی سا ل سے زیادہ عرصہ پربھی حُقْبٌ کا لفظ بولیں گے.اَلدَّھْرُ.زمانہ.اَلسَّنَۃُ وَقِیْلَ السِّنُوْنَ مطلق ایک سال کے عرصہ کےلئے بھی عربی میںلفظ حُقْب استعمال ہوتا ہے اور بعض کہتے ہیں کہ کئی سال کا عرصہ حُقْب کہلاتا ہے.(اقرب) تفسیر.لَابِثِیْنَ طَاغِیْنکی ضمیر کا حال ہے یعنی طاغیوں کا حال یہ ہوگا کہ وہ جہنم میں سالوں یا زمانوں یا صدیوں رہیں گے.اُخروی لحاظ سے تو بعد میں بحث کی جائے گی دنیوی لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں جب اسلام کوغلبہ حاصل ہوا تو وہ صدیوں تک ہی رہا.بعض قومیں دنیا میں فوراً پھیل جاتی ہیں لیکن اس کے بعد جلدی ہی مٹ جاتی ہیں.مگر مسلمانوں کا صدیوں تک غلبہ رہا.چنانچہ مسلمان قریباًسات سو سال تک غالب رہے اُن میں کمزوری بے شک چوتھی صدی میں ہی پیدا ہونی شروع ہو گئی تھی مگر مختلف صورتوں میں اُن کا غلبہ سات سو سال تک رہا ہے بلکہ وہ زمانہ جس میں مسلمانوں کے مقابلہ میں کوئی شخص اُٹھ نہیں سکتا تھا اور کسی کوجرأ ت نہیں ہوتی تھی کہ وہ مسلمانوں کے سامنے کھڑا ہو سکے اُس کو بھی شامل کر کے یہ ایک ہز ار سا ل کا عرصہ بن جاتا ہے.اب قریباً ساڑھے تین سو سال سے مسلمانوں کے مقابلہ میں غیر اقوام کھڑا ہونے کی جرأ ت ہوئی ہے اور انہوں نے سمجھا ہے کہ ہم بھی مسلمانوں کا مقابلہ کر سکتی ہیں.یعنی سترھویں صدی کے شروع سے مسلمان ایسے گرنے شروع ہوئے کہ دشمن اُن کے مقابلہ میں کھڑا ہو گیا لیکن اس سے پہلے ایک ہزار سال کے لمبے عرصہ میں کسی کو یہ جرأت نہیں ہوتی تھی کہ وہ مسلمانوں کے مقابلہ میں کھڑا ہو سکے اور یہ زمانہ دنیوی لحاظ سے گویادشمنان اسلام کے لئے دوزخِ حسد میں جلنے کا زمانہ تھا.احقاب کے معنے مفسرین کے نزدیک اَحْقَاب حُقُبٌ کی جمع ہے اس کے لغوی معنے حل لغات میں لکھے جا چکے ہیں اب اس کے تفسیری معنے لکھے جاتے ہیں.ابن جریر حضرت علیؓ سے روایت کرتے ہیں( عن سالم بن ابی الجہد) کہ حضرت علی ؓنے ہلال الہجری سے کہا کہ حُقْب کے معنے تم کیا کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ حُقْب کے معنے ہیںاسّی سال.ہر سال بارہ مہینے کا.ہر مہینہ تیس دن کااور ہر دن ایک ہزار سال کا.گویا یہ دو کروڑ اٹھاسی لاکھ سا ل ہوئے.ابن ابی حاتم نے حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت کی ہے.کہ حُقْب کے معنے ہیںچالیس سال جس کا ہر دن ہزار سال کا ہے گویا ایک کروڑ چوالیس لاکھ سال.اِسی قسم کی روایت ابن ابی حاتم نے ابن عباس سعید بن جبیر اور کئی تابعین سے بھی نقل کی ہے مگر حُقْب کو ستّر سال قرار دیا ہے( جملہ روایات منقول از ابن کثیر ہیں)گویا ان روایات کے مطابق ایک کروڑ چوالیس لاکھ یا دو کروـڑ اٹھاسی لاکھ یا دو کروڑ ساٹھ لاکھ سال کو اتنے عدد سے ضرب دی جائے گی جتنے عدداَحْقَاب کی جمع سے مراد
Page 55
لئے جائیں گے مگر یہ مقدار خواہ کچھ بھی ہو.بیس کروڑ ہو.چالیس کروڑ ہو یا ایک ارب ہو.بہرحال یہ ایک معیّن عدد ہے اور ان روایات سے اتنا ضرور ثابت ہو گیا کہ دوزخ کا عذاب محدود ہے اور وہ آخر ایک دن ختم ہو جائے گا.چنانچہ یہ احساس مفسّرین کے دلوں میں بھی پیدا ہوا ہے اور اسی وجہ سے مقاتل ابن حیان کہتے ہیں کہ یہ آیت فَذُوْقُوْافَلَنْ نَّزِیْدَکُمْ اِلَّا عَذَابًا کی آیت سے منسوخ ہے جو اسی رکوع کے آخر میں آتی ہے.حالانکہ مفسّرین اس بات پر متفق ہیں کہ یہ ساری آیتیں اکٹھی نازل ہوئی تھیں یعنی ا س سورۃ کا دو ٹکڑوں میں اترنا ثابت نہیں پس یہ بات عقل کے خلاف ہے کہ ایک ہی وقت میں یہ آیتیں نازل ہوئیں اکٹھی نازل ہوئیںاور پھر ان میں سے ایک آیت نے دوسری آیت کو منسوخ کر دیا.خالد بن معدان بھی کہتے ہیں (عن ابی جریر بحوالہ ابن کثیر زیر آیت ھذا ) کہ یہ منسوخ ہے.ان کی روایات لکھ کر ابن جریر کہتے ہیں کہ شاید یہ عبارتلَا يَذُوْقُوْنَ فِيْهَا بَرْدًا وَّ لَا شَرَابًا سے متعلق ہے یعنی لٰبِثِيْنَ فِيْهَاۤ اَحْقَابًا سے مراد محض دوزخ میں رہنا نہیں بلکہ اس قسم کا رہنا ہے جس کے متعلق اگلی آیت میں لَا يَذُوْقُوْنَ فِيْهَا بَرْدًا وَّ لَا شَرَابًا آیا ہے اور مراد یہ ہے کہ دوزخی دوزخ میں صدیوں ایسی حالت میں رہیں گے کہ نہ انہیں کوئی راحت ملے گی اور نہ پینے کو کچھ ملے گااس کے بعد بھی وہ رہیں گے تو دوزخ میں ہی مگر عذاب کی نوعیت بدل دی جائے گی پھر وہ کہتے ہیں وَالْاَصَحُّ اَنَّھَا لَا انْقِضَائَ لَھَا یعنی سچی بات تو یہ ہے کہ دوزخ کبھی مٹ ہی نہیں سکتا.لفظ احقاب سے دوزخ کے عذاب کے محدود ہونے کا احساس مفسرین کو پھر ابن جریر نے سالم سے اور انہوں نے حسن بصری سے یہ روایت نقل کی ہے کہ اَمَّا الْاَحْقَابُ فَلَیْسَ لَھَا عِدَّۃٌ اِلَّا الْخُلُوْدُ فِیْ النَّارِ (جامع البیان فی تفسیر القرآن جزء الثلا ثون زیر آیت ھذا) یعنی اَحْقَاب جمع کا لفظ خدا تعالیٰ نے بولا ہے اس کی گنتی بیان نہیں کی اس لئے اَحْقَاب کی گنتی غیرمحدود ہے اور اس سے مراد دوزخیوں کا ہمیشہ دوزخ میں رہنا ہے.اِن روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو ہر اک کے دل میں خیال پیداہوا ہے کہ اس آیت کے ظاہری معنے عذاب جہنم کے ختم ہونے پر دلالت کرتے ہیں لیکن پھر ان معنوں کی اپنے عقیدہ کے مطابق تاویل کرنے کی کوشش کی ہے اور یا تو اس آیت کو لَا يَذُوْقُوْنَ فِيْهَا بَرْدًا وَّ لَا شَرَابًا سے متعلق بتایا ہے اور یا اَحْقَاب کی جمع کو اَن گنت جمع قرار دے دیاہے.جہاں تک اَحْقَاب کی جمع کا سوال ہے یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ اَحْقَاب اوزانِ جمع قلّت میں سے ہے یعنی ان اوزان میں سے ہے جن کے معنے تین سے دس تک کے ہوتے ہیں اور گو ضروری نہیں کہ ہر جمع قلّت کے لفظ سے قلّت ہی مراد لی جائے مگر بہرحال وضع لفظ کو اہمیت ضرور دی جائے گی اور جس غرض کے لئے لغت نے لفظ مقرر کیا ہو اُس سے بدلنے کے لئے کوئی قرینہ ضرور ہونا چاہیے.بغیر کسی قرینہ کی موجودگی کے اُس کے دوسرے معنی کرنے جائز
Page 56
نہیں ہوں گے ورنہ تاویل کا ایسا دروازہ کھل جائےگاجو حقیقت سے بہت دُور لے جائے گاایسے قرینے بعض دفعہ معنوی ہوتے ہیں یعنی دُوسری آیات اُس پر دلالت کرتی ہیں یا دُوسرے شواہد اُس پر دلالت کرتے ہیں اور بعض دفعہ ظاہر ی ہوتے ہیں جیسے ال استغراقی آ جائے تو اس کے معنے جمع کثرت کے ہو جاتے ہیں یا کسی ایسے لفظ کی طرف اضافت ہو جو اُس کے ایسے معنے کر دے جو کثرت پر دلالت کرتے ہوں.مگر بغیر کسی قرینے کے کسی لفظ کو اُن معنوں سے پھرا دینا جو وضع لغت کے لحاظ سے صحیح ہوں جائز نہیں ہو سکتا اور وضع لغت کے لحاظ سے اَحْقَاب کے معنے تین سے دس تک کے ہو سکتے ہیں.پس اگر ہم اس کی آخری حد کو سمجھ لیں تو ہم دو کروڑ اٹھاسی لاکھ کو اس سے ضرب دے لیں گے بشرطیکہ ہم اَحْقَاب کے وہ معنے کریں جو تفاسیر میں کئے گئے ہیں.لیکن ہمارے پاس ایک اور حدیث ایسی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ روایت کہ وہاں ہر دن ہزار سال کا ہوگا رسول کریم صلے اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کی نہیں بلکہ غالباً یہود وغیرہ سے سنی ہوئی ہے.دوزخ کے غیر ابدی ہونے کا ثبوت حدیث سے بزّاز نے ایک روایت ابو مسلم بن العلاء سے نقل کی ہے کہ انہوں نے سلیمان التیمی سے پوچھا کہ کیا جہنم میں سے کوئی نکلے گا بھی یا نہیں ؟سلیمان التیمی نے جواب دیا کہ حَدَّثَنِیْ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَعَنِ النَّبِیِّ صَلَّی اللّٰہ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ اَنَّہٗ قَالَ وَاللّٰہِ لَایَخْرُجُ مِنَ النَّارِ اَحَدٌ حَتّٰی یَمْکُثَ فِیْھَا اَحْقَابًا قَالَ اَلْحُقْبُ بِضْعٌ وَّ ثَمَا نُوْنَ سَنَۃً کُلُّ سَنَۃٍ ثَلَاثُ مِائَۃٍ وَسِتُّوْنَ یَوْمًا مِمَّا تَعُدُّوْنَ (تفسیر ابن کثیر زیر آیت ھذا )یعنی مجھ سے بیا ن کیا نافع نے اُنہوں نے سنا عبدا للہ بن عمرسےاور عبداللہ بن عمر ؓ نے براہ راست رسول کریم صلے اللہ علیہ وآلہٖ وسلم سے یہ روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا خدا کی قسم آگ میں سے کوئی نہ نکلے گا جب تک اُس میں اَحْقَابیعنی کئی حُقْب نہ رہ لے.اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم دوزخ میں اَحْقَاب رہنے کے بعد وہاں سے نکلنے کے قائل ہیں مگر جن لوگوں کا عقیدہ اوپر بیان کیا گیا ہے اُن کے نزدیک اَحْقَاب سے مراد یہ ہے کہ دوزخ میں سے کوئی آدمی کبھی نہیں نکلے گا.پس اس روایت نے اُن کے خیالات کی تردید کر دی اور یہ ظاہر ہو گیا کہ رسول کریم صلے اللہ علیہ وَآلہٖ وسلم نے بھی اس کے معنے یہی لئے ہیں کہ اَحْقَاب کے بعد لوگ دوزخ میں سے نکل آئیں گے پھر آگے جو فرمایا گیا ہے کہ قَالَ اَلْحُقْبُ بِضْعٌ وَّثَمَانُوْنَ سَنَۃً کُلُّ سَنَۃٍ ثَلاثُ مِائَۃٍ وَسِتُّوْنَ یَوْمًا مِّمَّا تَعُدُّوْنَ یہ اگر رسول کریم صلے اللہ علیہ وآلہٖ وسلّم کے الفاظ ہیں تب بھی ان کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جنہوں نے یہ معنے کئے ہیںکہ حُقُبْ کا ہر دن ایک ایک ہزار سال کا ہوگا انہوں نے غلطی کی ہے اور یہ معنے انہوں نے یہود وغیرہ
Page 57
سے سُن کر نقل کر دیئے ہیںاور اگر قَالَ سے مراد حضرت عبداللہ بن عمرؓ ہیں تب بھی مِمَّا تَعُدُّوْنَ کے الفاظ بتاتے ہیں کہ وہ ان الفاظ کے ذریعہ ایک ہزار سال کا ایک دن ہونے کی تردید کرنا چاہتے ہیں.پس اگر یہ قول رسول کریم صلے اللہ علیہ وآلہٖ وسلّم کا ہو تب بھی وہ معنے غلط ثابت ہوتے ہیں اور اگر یہ قول حضرت عبداللہ بن عمرؓ کا ہو تب بھی یہ اُن معنوں کے غلط ہونے کی دلیل ہو گی کیونکہ ایک جلیل القدر صحابی ان معنوں کی تردید کر رہا ہے.تیسرا قرینہ اِن معنوں کے غلط ہونے کا حضرت علیؓ کی وہ روایت ہے جو سالم بن ابی الجعد سے منقول ہے اُس میں حضرت علیؓ ہلال الھجری سے پوچھتے ہیں کہ تم حُقْب کے کیا معنے کرتے ہوجس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول کریم صلے اللہ علیہ وآلہٖ وسلم سے حُقب کے کوئی خاص معنے مروی نہیں تھے اگر کوئی خاص معنےمروی ہوتے تو حضرت علیؓ ہلال الھجری کو وہ معنے بتاتے نہ یہ کہ ہلال الھجری سے اس لفظ کے معنے پوچھتے پس ان تمام استدلالات اور روایتوں سے یہ معلوم ہوا کہ اس جگہ دوزخ میں سے دوزخیوں کے نکلنے کا جواز بلکہ اُس کی خبر پائی جاتی ہے گو یہ بھی ضرور ہے کہ دوزخ میں رہنے کا ایک لمبا عرصہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے.اگراَحْقَاب سے مراد دس اَحْقَاب لئے جائیں اور حقب کے معنی اسّی سال کےلئے جائیں تب بھی آٹھ سو سال بن جاتے ہیں.یہ زمانہ بھی کوئی چھوٹا نہیں کیونکہ عذاب کی ایک گھڑی بھی بہت بڑی ہوتی ہے جیسا کہ میں نے بتایا ہے حُقُب کے معنے ایک لمبے زمانہ کے بھی ہوتے ہیں اور صدی کے بھی ہوتے ہیں.اگر صدی کے معنے لئے جائیں تو ایک ہزار سال کا زمانہ بن جاتا ہے اوراگر حُقْب سے مُراد لمبا زمانہ لیا جائے تو اَحْقَاب سے مراد دس لمبے زمانے ہوں گے.اس صورت میں یہ عذاب بہت لمبا بھی ہو سکتا ہے کیونکہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ اِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَاَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ (الحج:۴۸ ) کہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کا ایک زمانہ ہزار برس کا ہوتا ہے.اِس صورت میں اَحْقَاب سے مراد دس ہزار سال بن جائیںگے لیکن بہرحال کوئی معنے ہوں دوزخ کے عذاب کا غیر منتہی ہونا کہیں سے ثابت نہیں ہوتا.خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک اور جگہ پچاس ہزار سال کا بھی دن قرار دیا ہے جیسا کہ فرماتا ہے تَعْرُجُ الْمَلٰٓىِٕكَةُ وَ الرُّوْحُ اِلَيْهِ فِيْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ (المعارج :۵ ) اگر ایک حُقْب کو پچاس ہزار سال کا قرار دو تب بھی جہنم کا عذاب محدود ہی رہے گا غیر محدود ثابت نہیں ہو سکتا.لّٰبِثِيْنَ فِيْهَاۤ اَحْقَابًاکے الفاظ میں اسلام کے دشمنوں کے مغلوب ہونے کے زمانہ کی طرف اشارہ رسول کریم صلے اللہ علیہ وآلہٖ وسلّم کے دشمنوں کے دنیوی عذاب کے معنے کرنے کی صورت میں اس آیت میںیہ پیشگوئی نکلتی ہے کہ اسلام کے دشمن دو سو چالیس یا تین سو سے لے کر آٹھ سو یا ہزار سال تک مغلوب رہیں گے
Page 58
اسّی سال کا حُقْب مانا جائے تو چونکہ جمع قلّت تین سے دس تک ہوتی ہے تین سے اسّی کو ضرب دی جائے تو دو سو چالیس اور دس سے ضرب دی جائے تو آٹھ سو سال کا زمانہ بنتا ہے اور سو سال کا حُقْب مانا جائے توتین سوسے ہزار سال تک کا زمانہ ہوتا ہے)اگر کہو کہ اس طرح دو مُدتیں بتانے میں تو شک پیدا ہوتا ہے اور خدا تعالیٰ کے کلام میں شک نہیں ہوتا.تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس حد تک کلام میں ابہام کا ہونا کسی نئے فائدہ کو پیدا کرتا ہے اُسی حد تک خدا تعالیٰ کے کلام میں ابہام ہوتا ہے اور ہونا چاہیے.اس جگہ تین صدی سے دس صدی تک اسلام کے غلبہ کی خبر دینے میں دو فوائد تھے اس لئے یہ ابہام قبیح نہیں بلکہ حسن اور مفید ہے.اور وہ دو فائدے یہ تھے (۱)کہ دو سو چالیس سال یا تین صدیوں تک اسلام کا غلبہ نہایت مکمل اور اعلیٰ تھا یعنی اندرونی اتحاد اور بیرونی دشمن کی کمزوری دونوں باتیں پائی جاتی تھیں اور اسی عرصہ میں دشمن مکمل طور پرحسد کی آگ میں جل رہا تھا.کیونکہ نہ مسلمانوں کی کمزوری اُسے اپنی ترقی کی امید دلاتی تھی نہ اپنی طاقت کوئی امید کی صورت پیدا کرتی تھی.اس میں شک نہیں کہ سوسال کے بعد مسلمانوں میں ایک اختلاف رونما ہوا تھا.سپین اور بغداد الگ ہوئے مگر دو سو ستّر سال تک یہ اختلاف ایسا نمایاں نہیں ہوا کہ اس کا اثر اسلام کی ترقی پر پڑتا.اس کے بعد دو سو چالیس یا تین سو سال سے آٹھ سو یا ہزار سال تک کا زمانہ وہ ہے کہ اس میں ایک طرف مسیحیت کو طاقت ملنی شروع ہوئی دوسری طرف مسلمانوں میں کمزوری نمایاں طور پر پیدا ہونی شروع ہوئی.مگر مسیحیوں کی بیداری اور مسلمانوں کی کمزوری ایسی نہ تھی کہ اس کی وجہ سے مسلمانوں کے غلبہ کو نقصان پہنچے.خصوصًا اسی زمانہ کا متمدن علاقہ یعنے ایشیا اور شمالی افریقہ پوری طرح مسلمانوں کے تسلّط میں رہا.پسلّٰبِثِيْنَ فِيْهَاۤ اَحْقَابًا کی پیشگوئی حرف بحرف پوری ہوئی اور اِن دونوں زمانوں کے لحاظ سے اَحْقَاب کا لفظ جو مُبہم عدد پر دلالت کرتا ہے استعمال کیا گیا ہے.اَحْقَاب کی ابتدائی مدّت مکمل غلبہ پر دلالت کرتی ہے اور اس کی انتہائی مدّت اس غلبہ پر دلالت کرتی ہے جس میں کسی قدر ضعف کے آثار ظاہر ہونے لگ گئے تھے مگر غلبہ پھر بھی تھا.اس کے علاوہ اس ابہام کی ایک غرض یہ بھی ہے کہ پہلی تین صدیوں اور آخری سات صدیوں کے غلبہ میں ایک اور امتیاز بھی تھا.پہلی صدیوں میں اسلامی حکام پر کم وبیش عمل ہوتا تھااور کفّار سے حسن سلوک کا خیال رکھا جاتا تھا مگر تین سو سال کے بعد ملوکیّت نے زور پکڑلیا اور کفّار سے نسبتًا سختی شروع ہو گئی جو غیر مذاہب والوں کے سلوک سے تو بہتر تھی مگر اسلامی معیار کے مطابق نہ تھی اس وجہ سے بھی ایسا لفظ استعمال کیا گیا ہے جس سے دو قسم کے سلوکوں کے الگ الگ زمانوں پر دلالت ہو یعنی تین سو اور ہزار سال کے زمانہ پر.ان معنوں کے رُو سے فَلَنْ نَّزیْدَکُمْ اِلَّا عَذَابًا کی آیت بھی خوب حل ہوتی ہے کیونکہ اس آیت میں زمانہ کے ساتھ ساتھ عذاب کی زیادتی کی طرف اشارہ
Page 59
کیا گیا ہے اور یہی حال کفّار کا ہوا.ابتداء ً اسلام میں اسلامی تعلیم کے ماتحت ان پر سختی نہ کی جاتی تھی لیکن جوں جوں اسلامی تعلیم کا اثر مسلمانوں کے دلوں سے کم ہوتا گیا مسلمانوں میں سختی پیدا ہوتی گئی اور اسلامی حکومتوں کے دشمنوں پر تعذیب بڑھتی گئی.غرض اس آیت کا جہاں تک غلبۂ اسلام سے تعلق ہے اس آیت کے یہ معنے ہیں کہ مسلمانوں کا غلبہ تین سو سال سے ایک ہزار سال تک رہے گا اور ایسا ہی ہوا.اس میں کوئی شک نہیں کہ درمیان میں عارضی طور پر ترکوں کی ایک رَو آئی جس نے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا مگر وہ بھی کچھ عرصہ کے بعد مسلمان ہو کر دب گئے اور اسلام کو ہی غلبہ حاصل رہا.اس صورت میں یہی نہیں کہ اسلام کی ترقی اور کفر کی بربادی کی اس آیت میں خبر دی گئی ہے بلکہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اسلام کو جو غلبہ حاصل ہو گاوہ ایک ہزار سال تک چلتا چلا جائے گا.ایک ہزار سال کے غلبہ کے بعد کفر پھر سر اٹھائے گا اور مسلمانوں کا تنزّل شروع ہو جائے گا.چونکہ ہر مضمون کے لحاظ سے آیتوں کے معنے کئے جاتے ہیں اس لئے اسلام اور رسول کریم صلے اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کے غلبہ کے لحاظ سے اس کے یہی معنے ہوں گے.لیکن جب ہم ان آیات کو عذاب دوزخ کے متعلق قرار دیں گے تو اس صورت میں ہم یہ کہیں گے کہ حُقْب سے مراد زمانہ ہے اور اَحْقَاب سے مراد بہت لمبا زمانہ ہے.عذاب جہنم کے منقطع ہونے کے پانچ ثبوت قرآن مجید سے علاوہ ازیں قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ دوزخ کا عذاب غیر منقطع نہیں اس لئے بھی اَحْقَاب کو اس کے معنوں سے پھرانے کی اجازت نہ ہو گی.چنانچہ فرماتا ہے (۱)اُمُّہٗ ھَاوِیَۃٌ (القارعۃ:۱۰) دوزخ دوزخیوں کی ماں کی طرح ہو گی جس طرح ماں کے رحم میں انسان کی تکمیل ہوتی ہے اسی طرح دوزخ میں دوزخیوں کی روحوں کی تکمیل کی جائے گی اور ظلمات ثلاثہ میں سے گزر کر آخر ایک دن وہ نئی روحانی پیدائش حاصل کر لیں گے (۲)د وسرے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَحْمَتِیْ وَسِعَتْ کُلَّ شَیْءٍ (اعراف :۱۵۷) میری رحمت نے ہر چیز کو ڈھانپا ہوا ہے.جب اللہ کی رحمت نے ہر چیز کو ڈھانپا ہؤا ہے تو دوزخیوں کو بھی اُسے اپنی رحمت سے ڈھانپنا چاہیے اس آیت سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ آخر انسان نجات پا جائے گا (۳) تیسرے فرماتا ہے رَبَّنَا وَسِعْتَ کُلُّ شَیْ ئٍ رَّحْمَۃً وَّعِلْمًا (المومن:۸) اے ہمارے رب ہر چیز کا تو نے رحمت اور علم سے احاطہ کیا ہوا ہے.اگر اس کی آیت کی موجودگی میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی چیز بھی مخلوق میں سے ایسی ہے جس کا خدا کو علم نہیں تو یہ کس طرح کہا جا سکتا ہے کہ کوئی بھی چیز ایسی ہے جس کو خدا کی رحمت ڈھانپ نہیں لے گی.(۴) چوتھے فرماتا ہے خٰلِدِيْنَ فِيْهَا مَا دَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَ الْاَرْضُ اِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ١ؕ اِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا
Page 60
يُرِيْدُ(ھود:۱۰۸) وہ اُس میں اُس وقت تک رہیں گے جب تک کہ آسمان اور زمین ہیں اِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ مگر جو تیرا رب چاہے یعنی تیرا رب جس کو بخشنا چاہے بخش دے اِنَّ رَبَّکَ فَعَّالٌ لِّمَا یُرِیْدُ تیر ا رب وہ بات ضرور کرے گا جس کا وہ ارادہ رکھتا ہے.اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ بخشش کر نے والا ہے بلکہ یہ بھی بتا دیا کہ اُس کی طرف سے بخشش ہو گی بھی.(۵) اسی طرح سورۂ ھود میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِلَّا مَنْ رَّحِمَ رَبُّکَ وَلِذَالِکَ خَلَقَہُمْ (ھود:۱۲۰) سوائے ان کے جن پر تیرے رب نے رحم کیا وَلِذَالِکَ خَلَقَھُمْ اور اسی لئے اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کو پیدا کیا ہے تا کہ اُن پر رحم کرے.جب ہر مخلوق کو خدا تعالیٰ نے رحم کے لئے پیدا کیا ہے تو یہ خیال کر لینا کہ وہ کسی کو ہمیشہ کے لئے دوزخ میں رہنے دے گا اس آیت کے بالکل خلاف ہے.ابن کثیر میں حضرت ابن عباسؓ سے روایت آتی ہے کہ لِلرَّحْمَۃِ خَلَقَہُمْ وَلَمْ یَخْلُقْہُم لِلْعَذَابِ (تفسیر ابن کثیر زیر ھود ۱۱۹)یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو اپنی رحمت کے لئے پیدا کیا ہے عذاب کیلئے پیدا نہیں کیا.اور یہ ایک لازمی بات ہے کہ جس چیز کے لئے کسی کو پیدا کیا گیا ہے وہ اس کو ضرور مل جانی چاہیے (۶)پھر فرماتا ہے فَمَنْ یَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّۃٍ خَیْرًا یَّرَہٗ (الزلزال:۸) جو شخص ایک ذرّہ بھر نیکی میں بھی حصہ لے گا اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کے ایک ذرّہ کو بھی ضائع نہیں کرے گا اور وہ ضرور اس کا انجام دیکھے گا.یہ انجام وہ اسی طرح دیکھ سکتا ہے کہ پہلے اُسے گناہوں کی سزا دے دی جائے اور بعد میں اُسے معاف کر دیا جائے.(۷) حدیث میں بھی آتا ہے اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰہِ صَلَّی للّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ قَالَ یَقُوْلُ اللّٰہُ عَزَّوَجَلَّ اِذَااَرَادَ عَبْدِیْ اَنْ یَّعْمَلَ سَیِّئَۃً فَلَا تَکْتُبُوْھَا عَلَیْہِ حَتّٰے یَعْمَلَھَافَاِنْ عَمِلَھَا فَاکْتُبُوْا ھَابِمِثْلِھَاوَاِنْ تَرْکَھَا مِنْ اَجْلِیْ فَاکْتُبُوْھَا لَہٗ حَسَنَۃً وَاِذَااَرَادَ اَنْ یَّعْمَلَ حَسَنَۃً فَلَمْ یَعْمَلْھَا فَاکْتُبُوْھَا لَہٗ حَسَنَۃً فَاِنْ عَمِلَھَا فَاکْتُبُوھَا لَہٗ بِعَشْرِ اَمْثَالِھَا اِلَی سَبْعِ مِأتِ ضِعْفٍ (بخاری مصری جلد رابع کتاب التوحید باب قول اللہ تعالیٰ یریدون ان یبدلوا کلام اللہ) یعنی ہر بدی کی سزا اُس کے برابر ہے اور ہر بدی جس کا خیال چھوڑ دیا جائے اس کے بدلہ میں نیکی لکھی جاتی ہے اورہر نیکی جس کا انسان خیال کرے خواہ عمل نہ کرے اس کے بدلہ میں نیکی ہے اور ہر نیکی کا بدلہ دس سے سات سوگنے تک ہے.قرآن کریم میں بھی نیکی کا دس گنے سے زیادہ ثواب دیئے جانے کا وعدہ کیا گیا ہے جیساکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ١ؕ وَ اللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ١ؕ وَ اللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ (البقرۃ :۲۶۲)یعنی جو لوگ اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اُن کے اس فعل کی حالت اُس دانہ کی حالت کی مشابہ ہے جو سات بالیں اُگائے اور ہر بال میں سو دانہ ہو اور اللہ جس کے لئے چاہتا ہے اس سے بھی بڑھا بڑھا کر دیتا ہے اور اللہ وسعت والا ہے اور بہت
Page 61
جاننے والا ہے.اس آیت سے پتہ لگتا ہے کہ بعض نیکیوں کا بدلہ سات سات سو گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے.چونکہ انسان میںکچھ نیکی بھی پائی جاتی ہے اس لئے نیکیوں کا شمار اگر اس حدیث اور قرآن کریم کی آیت کے مطابق کیا جائے تو عقل اس بات کو جائز قرار نہیں دیتی کہ کوئی انسان دائمی طور پر نجات سے محروم ہو جائے.(نیز دیکھو تفسیر کبیر جلد ۴ سورۃ ہود زیر آیت ۱۰۹) لَا يَذُوْقُوْنَ فِيْهَا بَرْدًا وَّ لَا شَرَابًاۙ۰۰۲۵اِلَّا حَمِيْمًا (وہاں ان لوگوں کی یہ حالت ہو گی) کہ وہ نہ تو اس میں کسی قسم کی ٹھنڈک (محسوس کریں گے) اور نہ کوئی پینے کی چیز وَّ غَسَّاقًاۙ۰۰۲۶جَزَآءً وِّفَاقًاؕ۰۰۲۷ چکھیں گے سوائے (تیز) گرم پانی اور (ناقابل برداشت) ٹھنڈے پانی کے ( اس طرح انہیں ان کے اعمال کے) مطابق بدلہ(دیا جائے گا).حل لغات.اَلْبَرْدُ نَقِیْضُ الْحَرِّ.بَرْد کے معنے ٹھنڈک کے ہیں اَلْبَرْدُ اَیْضًا اَلنَّوْمُ.بَرْد کے ایک معنے نیند کے بھی ہیں چنانچہ عرب کہتے ہیں اَلْبَرْدُ یَمْنَعُ الْبَرْدَ یعنی ٹھنڈک نیند کو روک دیتی ہے(اقرب) فتح البیان میں ہے کہ حسن.عطا اور ابن زید کے نزدیک بَرْد سے مراد راحت ہے.(فتح البیان زیر آیت ھذا) حَمِیْمًا اَلْحَمِیْمُ اَلْمَاءُ الْحَارُّ.حَمِیْم گرم پانی کو کہتے ہیں یہ لفظ اضداد میں سے ہے یعنی اپنے مخالف معنے بھی ادا کرتا ہے چنانچہ اس کے معنے ٹھنڈے پانی کے بھی ہیں.نیز اَلْحَمِیْمُ کے معنے ہیں اَلْقَیْظُ.گرمی اَلْعَرْقُ پسینہ.(اقرب) غَسَّاق اَلْغَسَّاقُ کے معنے ہیںاَلْمُنْطِنُ الْبَارِدُ اَلشَّدِیْدُ الْبَرْدِالَّذِیْ یُحْرِقُ مِنْ بَرْدِہٖ کَاِحْرَاقِ الْحَمِیْمِ سخت ٹھنڈی بدبودار چیزجو اپنی ٹھنڈک سے ایسی ہی تکلیف دے جیسے کہ گرم پانی گرمی سے جلا دیتا ہے (لسان) مَایَقْطُرُ مِنْ جُلُوْدِ اَھْلِ النَّارِ وَصَدِیْدُھُمْ مِّنْ قَیْحٍ وَنَحْوُہٗ وہ پیپ جو دوزخیوں کے اجسام سے نکلے گی اُس کو بھی غَسَّاق کہتے ہیں.(اقرب) وِفَاقًا: وِفَاق وَافَقَ کا مصدرہے اور وَافَقَ عَلَی الشَّیْ ئِ کے معنے ہیں ضِدُّ خَالَفَ کسی چیزکے مطابق آیا.اَلْوَفْقُ کے معنے ہیں اَلْمُطَابَقَۃُ بَیْنَ الشَّیْئَیْنِ دو اشیاء کے درمیان پوری مطابقت (مفردات)پس
Page 62
جَزَآءً وِّفَاقًا کے معنے ہوںگے اعمال کے مطابق جزاء.تفسیر.لَا یَذُوْقُوْنَ فِیْھَا یہ طَاغِیْنَ کا دوسرا حال ہے.پہلا حال آیت لّٰبِثِيْنَ فِيْهَاۤ اَحْقَابًا میں بیان ہے.یعنی طاغیوں کا یہ حال بھی ہو گا کہ وہ نہیں چکھیں گے بَرْد اور نہ ہی شَرَاب اس حالت میں کہ وہ جہنّم میں ہوں گے جو ابن جریر نے معنے کئے ہیں کہلّٰبِثِيْنَ فِيْهَاۤ اَحْقَابًا والی آیت لَا یَذُوْقُوْنَ فِیْھَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا سے متعلق ہے اس کا مطلب یہ تھا کہ پھر عذاب کی نوعیت بدل جائے گی مگریہ معنے بالبداہت باطل ہیں.کیونکہ اس صورت میں آیت کے معنےیہ بنتے ہیں کہ اَحْقَاب کے بعد اُنہیں راحت بھی میسّر آجائےگی اور پینے کے لئے پانی بھی ملنا شروع ہو جائے گا.جب انہیں پانی بھی مل جائے گا اور راحت بھی میسّر آجائے گی تو پھر عذاب کس بات کا ہو گا.اگر خالی پینے کا ذکر ہوتا تو ہم کہہ سکتے تھے کہ صرف پانی پینے کے بعد بھی دکھ رہ سکتا ہے مگر یہاں توشَرَابًا کے ساتھ ہی بَرْدًا کا بھی ذکر آتا ہے اور بَرْدًا کے معنے نیند اور راحت کے بھی ہوتے ہیں.پسلَا یَذُوْقُوْنَ فِیْھَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا کے معنے یہ ہوں گے کہ اَحْقَاب تک تو انہیں راحت نہیں ملے گی اور نہ پینے کے لئے پانی ملے گا مگر جب اَحْقَاب گزر جائیں گے تو پھر انہیں پینے کے لئے پانی بھی مل جائے گا اور نیند اور راحت کے سامان بھی میسّر آجائیںگے لیکن وہ رہیں گے دوزخ میں ہی.پس یہ معنے بالبداہت غلط اور باطل ہیں.لَا يَذُوْقُوْنَ فِيْهَا بَرْدًا سے ابن جریر کا غلط استدلال دوسرے بَرْدًا وَلَا شَرَابًا میں بَرْدًا کو الگ بیان کیا گیا ہے اور شَرَابًا کو الگ بیان کیا گیا ہے جس سے صاف پتہ لگتا ہے کہ یہاں بَرْدًا سے ٹھنڈا پانی مراد نہیں بلکہ کچھ اور مراد ہے اور وہ معنے یہی ہو سکتے ہیں کہ انہیں راحت کے سامان بھی میسّر نہیں آئیں گے.چنانچہ بَرْد کے ایک معنےراحت کے بھی آتے ہیںچنانچہ لکھا اَلبَرْدُ: اَلرَّوْحُ وَالرَّاحَۃُ (فتح البیان) جہاں تک قیامت کا تعلق ہیلَا یَذُوْقُوْنَ فِیْھَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا کے معنے ظاہری بھی کئے جا سکتے ہیں کہ وہاں اُن کے لئے کوئی راحت کا سامان نہیں ہو گااور نہ انہیں پینے کے لئے کوئی چیز ملے گی سوائے گرم پانی اور غَسَّاق کے.غَسَّاق کے معنے ہوتے ہیں سخت سرد پانی یا بد بودار پانی کے یا وہ پیپ جو زخموں میںسے بہتی ہے چنانچہ لُغت میں لکھا اَلغَسَّاقُ.اَلْمُنْتِنُ.اَلْبَارِدُالشَّدِیْدُالْبَرْدِ.وَمَا یَقْطُرُمِنْ جُلُوْدِاَھْلِ النَّارِ وَصَدِیْدُھُم مِنْ قَیْحٍ وَ نَحْوُہٗ (اقرب) غَسَّاق کا لفظ بھی بتا رہا ہے کہ یہاں بَرد کے معنے راحت کے ہی ہیں کیونکہ غَسَّاق کے معنے ہیں سخت سرد.پس یہ کہنا کہ انہیں وہاں سردی نہیں لگے گی بالبداہت باطل ہو گیا کیونکہ غَسَّاق کے معنے ہی سخت سرد کے ہیں.غرض اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دوزخیوں کو جو پانی ملے گاوہ سخت گرم ہو گا.اسی طرح اُنہیں زخموں کا دھوون یعنی
Page 63
اس کی پیپ دی جائے گی یا سخت بد بودار اور سڑا ہوا پانی ملے گا.یا اتنا ٹھنڈا پانی دیا جائے گا جس سے ان کے دانت گرنے لگیں گے.جَزَآءً وِّفَاقًاکا مطلب جَزَآءً وِّفَاقًایعنی یہ جزا ہے جو اُن کے مناسب حال ہے.وِفَاقًا کے معنے ہوتے ہیں مُوَافِقًا لِلْاَعْمَالِ وہ جزا جو اُن کے اعمال سے مطابقت رکھتی ہے یعنی اُس دنیا میں بھی اُن کے اندر میانہ روی نہیں تھی اور چونکہ دُنیا میں میانہ روی کا وصف اُن کے اندر نہیں پایا جاتا تھا اس لئے اگلے جہان میں بھی انہیں ایسی ہی چیزیں ملیں گی جو حد درجہ گرم ہوں گی یا حد درجہ سرد ہوں گی یا چونکہ دنیا میں وہ سخت غصہ میں آجاتے تھے یا نکمے اور سُست ہو کر بیٹھ رہتے تھے.میانہ روی کی عادت جو انسان کو کامیاب کرتی ہے ان کے اندر نہیں تھی اس لئے جہنّم کا عذاب بھی انہیں اسی صورت میں ہی ملے گا.کہیں سخت گرم پانی اُن کو پینے کے لئے ملے گاکہیں سخت سرد پانی اُن کو پینے کے لئے ملے گا.درمیانی پانی جو راحت بخشتا ہے انہیں جہنّم میں نظر ہی نہیں آئے گا.اسلام اور کفر کے اخلاق میں یہی فرق ہے کہ اسلام میں میانہ روی کی تعلیم ہے لیکن اسلام کے علاوہ اور کسی مذہب میں میانہ روی کی تعلیم نہیں پائی جاتی.یہودیت کہتی ہے ’’جان کے بدلے جان لےاور آنکھ کے بدلے آنکھ دانت کے بدلے دانت اور ہاتھ کے بدلے ہاتھ اور پائوں کے بدلے پائوں.جلانے کے بدلے جلانا.زخم کے بدلے زخم اور چوٹ کے بدلے چوٹ ‘‘ (خروج باب ۲۱آیت ۲۳تا ۲۵)عیسائیت کہتی ہے ’’جو کوئی تیرے داہنے گال پر طمانچہ مارے دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے ‘‘ (متی باب۵ آیت ۳۹)گویا ایک میں گرمی ہی گرمی چلتی چلی جاتی ہے اور دوسرے میں سردی ہی سردی چلی جاتی ہے.پس ایسے اعمال کے بدلہ میں جزاء بھی ایسی ہوگی کسی کو گرمی ہی گرمی پہنچے گی.لیکن اسلام اپنے تمام احکام میں میانہ روی کی تعلیم دیتا ہے.وہ فرماتا ہے تم رحم کے موقع پر رحم کرو اور سزا کے موقع پر سزادو.چنانچہ قرآن کریم میں آتا ہے.وَ جَزٰٓؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا١ۚ فَمَنْ عَفَا وَ اَصْلَحَ فَاَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ١ؕ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ (الشوریٰ:۴۱) یعنی بدی کی سزا اُسی حد تک دینی جائزہے جس حد تک کہ ظالم نے ظلم کیاتھا مگر جو ظلم کے مقابل پر عفو سے کام لے بشرطیکہ اس عفو سے اصلاح ہوتی ہو تو اُسے اپنے اس عفو کا بدلہ اللہ تعالیٰ سے ملے گا اور ضرور ملے گا.قرآن مجیداور رسول کریم صلے اللہ علیہ وآلہٖ وسلّم کے متعلق اگر ان آیتوں کو لیا جائے تو پھر ان سے روحانی معنی مراد ہوں گے جیسا کہ پہلے روحانی معنے کرتے چلے آئے ہیں.یعنی اسلام کے دشمنوں کو کبھی راحت نہیں ملے گی.اُن کے دلوں کو کبھی چین نصیب نہیں ہو گا وہ اسلام کے مقابلہ میں جب اپنی ناکامی دیکھیں گے تو اس بے چینی اور اضطراب کی حالت میںکبھی وہ اسلام کے مقابلہ میں بالکل مایوس ہو کر بیٹھ جائیں گے اور کبھی پاگلوں کی طرح اُٹھ کر
Page 64
حملہ کرنا شروع کر دیں گے حَمِیْمًاوَّ غَسَّاقًا والی حالت یہی ہوتی ہے کہ کبھی انسان جوش میں آکر پاگلوں کی طرح کام کرنے لگ جائے اور کبھی ہمت ہار کر بیٹھ جائے.یہ دونوں حالتیں ایسی ہیں جو انسان کو کامیابی سے دُور رکھتی ہیں.نہ پاگلوں کی طرح حملہ کرنے والا جیت سکتا ہے اور نہ مایوسی کی حالت میں قوت عمل سے کام نہ لینے والاکبھی کامیاب ہو سکتا ہے.لیکن فرماتا ہے جب اس حالت پر اَحْقَاب گزر جائیں گے تو اس کے بعد ان کو ہوش آجائے گی اور وہ منظم طور پر مسلمانوں پر حملہ کرنا شروع کر دیں گے اُس وقت چونکہ مُسلمان بھی اپنے بُرے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے غضب کو بڑھا چکے ہوں گے اس لئے ایک طرف اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور دوسری طرف کفر کا منظم حملہ.جب یہ دو چیزیں مل جائیں گی تو پھر کفّار جیت جائیں گے.اِنَّهُمْ كَانُوْا لَا يَرْجُوْنَ حِسَابًاۙ۰۰۲۸ وہ یقیناً (کسی) محاسبہ کا ڈر (اپنے دلوں میں ) نہیں رکھتے تھے.حل لغات.لَا یَرْجُوْنَ: رَجَا سے مضارع منفی کا جمع مذکّر کا صیغہ ہے اور رَجَا الشَّیْ ئَ کے معنے ہیں اَمَّلَ بِہٖ اس کی امید رکھی.خَافَ.کسی چیز سے ڈرا (اقرب)پس کَانُوْالَایَرْجُوْنَ کے معنی ہوںگے (۱)وہ امید نہیں رکھتے (۲) وہ ڈرتے نہ تھے.اَلْحِسَابُ الحساب کے معنے ہیں اَلْعَدُّ: شمار کرنا.گننا.(اقرب ) تفسیر.آخرت کے لحاظ سے اس کے معنے یہ ہوں گے کہ بعث بعد الموت پر چونکہ یقین نہیں تھا اس لئے وہ ایسے کام نہیںکرتے تھے جو ان کو اگلی زندگی میں فائدہ پہنچانے والے ہوتے.اُن کےکاموں کی اصل غرض دنیوی حالات ہؤا کرتے تھے صحیح محرّک اُن کے قلب میں نہیں تھا اس لئے وہ نیکی کو نہیں پا سکتےتھے.يَرْجُوْنَ کے دو معنی یَرْجُوْنَ کے معنے خوف کرنے کے بھی ہوتے ہیں اور امید رکھنے کے بھی.لَا يَرْجُوْنَ حِسَابًاکے معنی آخرت کے لحاظ سے اور آخرت کے لحاظ سے یہ دونوں معنی چسپاں ہو سکتے لَایَرْجُوْنَ حِسَابًا وہ خوف نہیں کرتے تھے کہ ہمارے اعمال کی سزا ہم کو ملے گی یا وہ امید نہیں کرتے تھے کہ اگر ہم نیک اعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اُن کا کوئی بدلہ ملے گا.اس لئے رَجَاء کا لفظ یہاں استعمال کیا گیا ہے قرآن کریم کی یہ خوبی ہے کہ وہ ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے جو ایک ہی وقت میں کئی کئی معنوں میں مستعمل ہو
Page 65
جاتے ہیں.یہاں بھی رَجَاء کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جو دو معنوں کی طرف اشارہ کرتا ہے یعنی امید اور خوف.درحقیقت انسانی اعمال میں دو وجوہ سے ہی خرابی پیدا ہوتی ہے یا تو اس وجہ سے خرابی پیدا ہوتی کہ بد اعمال کی سزا کا اُسے کوئی ڈر نہیں ہوتا اور یا اس وجہ سے خرابی ہوتی ہے کہ نیک اعمال کی جزاء کا اُسے یقین نہیں ہوتا.اِنَّھُمْ کَانُوْا لَایَرْجُوْنَ حِسَابًا یہ دونوں باتیں بیان کر دی گئی ہیں یہ بھی کہ وہ اس بات سےنہیں ڈرتے تھے کہ اُن کے اعمال کا محاسبہ ہوگا اور یہ بھی کہ وہ امید نہیں رکھتے تھے کہ اگر وہ نیکی کریں گے تو انہیں اس کا کچھ بدلہ ملے گا.دنیوی زندگی کے متعلق ا س آیت کو سمجھا جائے تب بھی یہ دونوں معنے چسپاں ہوتے ہیں یعنی قرآن مجید اور محمد صلے اللہ علیہ وآلہٖ وسلم سے انہوں نے اس لئے تعلق پیدا نہیں کیا اور اس لئے وہ مغضوب اور مقہور بن گئے کہ اُنہیں اس امر کا ڈر نہ تھا کہ ان کو اُن کی بدیوں کی سزا ملے گی.وہ کہتے تھے کہ ہم کیوں بدیاں چھوڑ یں ہمیں کسی کاڈر نہیں ہے.اور پھر اس کے ساتھ ہی وہ اس امر کی بھی امید نہیں رکھتے تھے کہ انہیں نیک اعمال کا اچھا بدلہ ملے گا.اور اس وجہ سے نماز ،روزہ اور دوسری اسلامی قیود کی طرف اُن کا دل مائل نہیں ہوتا تھا.لَا يَرْجُوْنَ حِسَابًامیں دشمنان اسلام کے اندر مایوسی پیدا ہوجانے کی طرف اشارہ اسلام کے مقابلہ کے لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان آیات کا یہ مطلب ہے کہ اُن کے دلوں میں سخت بُغض اور کینہ ہو گا وہ پوری کوشش کریں گے کہ اسلام مٹ جائے اور وہ کسی خطرہ کی پرواہ نہیں کریں گے مگر ساتھ ہی لَایَرْجُوْنَ حِسَابًا وہ کامیابی کی امید نہیں رکھیں گے.اُن کے دلوں میں مایوسی پیدا ہو جائے گی اور وہ خیال کریں گے کہ اب کفر کو فتح حاصل نہیں ہو سکتی.اور جس شخص کے اندر مایوسی پیدا ہو جائے اس کی دو ہی صورتیں ہوتی ہیں یا تو پاگلوں کی طرح حملہ کرتا ہے یا پھر مایوس ہو کر بیٹھ جاتا ہے.وَّ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا كِذَّابًاؕ۰۰۲۹ اور ہمارے نشانات کو سختی کے ساتھ جھٹلاتے تھے.حل لغات.کَذَّ بُوْا: کذَّبَ سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے اور کذَّبَ الْاَمْرَ تَکْذِیبًا وَّکِذَّابًا کے معنے ہیں اَنْکَرَہٗ وَجَحَدَہٗ کس چیز کا شدت سے انکار کیا.جھٹلایا(اقرب) پس کذَّبُوا کے معنے ہوں گے.انہوں نے جھٹلایا.انکار کیا.
Page 66
کِذَّاب: کَذَّبَ کا مصدر ہے جس کے معنے جھٹلانے کے ہوتے ہیں.تفسیر.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ہمارے نشانوں کو سخت جھٹلایا کرتے تھے یعنی نشانوں کے جھٹلانے کی وجہ سے ایمان لانے کی طرف اُن کو کوئی توجہ نہیں تھی.كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا کے دو معنی كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا كِذَّابًا اگر شروع زمانہ کے کافروں کے متعلق سمجھا جائے تو اس لحاظ سے اس آیت کے یہ معنے ہوں گے کہ چونکہ یہ لوگ ہماری ان پیشگوئیوں کو کہ اسلام کو غلبہ حاصل ہوگا اور قیامت آئے گی نہیں مانتے تھے اس لئے گمراہ ہو گئے.قیامت پر یہ معنی اس طرح چسپاں ہو سکتے ہیں کہ چونکہ وہ قیامت کے منکر تھے اس لئے اُن کی یہ حالت ہوئی اور اگر کلام الٰہی یا رسول کریم صلے اللہ علیہ وآلہٖ وسلم مراد لئے جائیںتو پھریہ مطلب بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اُن نشانات کو نہ مانتے تھے جو رسول کریم صلے اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کے ہاتھ پر ظاہر ہوئے.اسی طرح آیات سے مراد کلام الٰہی بھی ہو سکتا ہے.پسكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا كِذَّابًا کا یہ مطلب ہو گا کہ چونکہ کلام الٰہی سے اُن کی فطر ت کا جوڑ نہیں اس لئے وہ اس کا قطعی طور پر انکار کرتے ہیں.وَ كُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنٰهُ كِتٰبًاۙ۰۰۳۰ اور ہم نے (تو) ہر ایک چیز کو (پوری ) ٭ پوری طرح گن رکھا ہے.حل لغات.اَحْصَیْنَاہُ : اَحْصٰی سے متکلم مع الغیر کا صیغہ ہے.اور اَحْصٰی الشَّیْءَ اِحْصَاءً کے معنے ہیں عَدَّہُ کسی چیز کو گنا ہ اور شمار کیا (اقرب)پس اَحْصَیْنٰہُ کے معنے ہوں گے.ہم نے اس کو گن لیا.کِتَابًا: اَحْصٰی کا مفعول مطلق بھی ہو سکتا ہے اور حال بھی.مفعول مطلق ہونے کی صورت میں اس کے معنے یہ ہوں گے کہ ہم نے ہر چیز کو پوری طرح گن رکھا ہے.اور حال ہونے کے لحاظ سے اس کے یہ معنی ہوں گے کہ اَحْصَیْنٰہُ حَالَ کَوْنِھَا کِتَابًا اَیْ مَکْتُوْبًا.یعنی ہم نے ہر چیز کو اس حال میں گن چھوڑا ہے کہ وہ لکھی ہوئی ہے.کیونکہ کِتَاب بمعنے مَکْتُوْب بھی آتا ہے.کتاب کے معنے ہیں.مَایُکْتَبُ فِیْہِ.وہ اوراق جن میں لکھا جاتا ہے.اَلْقَدْرُ.قدر.اَلْحُکْمُ.حکم.٭ اصل لفظی ترجمہ اس آیت کا یوں ہوگا کہ ہم نے ہر ایک شے کو گن رکھا ہے گن رکھا ہےپوری طرح.چونکہ گن رکھا ہے کا جملہ پہلے محذوف ہے اس لئے اردو میں اس کو ادا کرنے کے لئے پوری پوری طرح گن رکھا ہے ترجمہ کیا گیا ہے.
Page 67
اَلْفَرْضُ.فرض.اَلدَّوَاۃُ.دوات (اقرب) تفسیر.کوئی انسانی عمل ضائع نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ہر چیز کا اچھی طرح اندازہ کر رکھا ہے یا ہر چیز کو ہم نے ایک اندازہ کی جگہ میں محفوظ کر رکھا ہے.مطلب یہ کہ وہ ایسی جگہ محفوظ ہیں جہاں سے کوئی چیز ضائع نہیں ہو سکتی.چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کوئی انسانی عمل ایسا نہیں جو ضائع ہو جا تا ہو بلکہ وہ ضرور کسی نہ کسی شکل میں محفوظ ہوتا ہے.ریڈیو کی ایجاد نے اس صداقت کو بہت بڑا ثبوت مہیا کر دیا ہے ہزاروں ہزار میل پر ایک شخص اپنی زبان سے کوئی لفظ نکالتا ہے تو فوراً ہم تک پہنچ جاتا ہے اور ہم گھر بیٹھے ہزاروں ہزار میل دور کی آواز اس طرح سُن لیتے ہیں جیسے وہ ہمارے پاس بیـٹھا باتیں کر رہا ہے.مجھے خیال آیا کرتا ہے کہ کوئی تعجب نہیں اگر یہ علوم ترقی کرتے کرتے اس حالت کو پہنچ جائیں کہ گزشتہ زمانہ کی آوازوں کو بھی ریکارڈ کیا جاسکے.اگر کوئی ایسا آلہ نکل آئے تو ہو سکتا ہے ہم رسول کریم صلے اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کی وہ حدیثیں جو آج کتابوں میں پڑھتے ہیںخود رسول کریم صلے اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کی زبان سے سن لیں.یہ بات موجودہ زمانہ کی ایجادات کو دیکھتے ہوئے اب ناممکن نظر نہیں آتی.زمانہ بہت ترقی کر چکا ہے ممکن ہے آئندہ چل کر کوئی ایسا آلہ ایجاد ہو جائے اور گزشتہ زمانہ کو بھی اپنے کنٹرول میں لایا جاسکے.اس صورت میں ہمیں گزشتہ زمانہ کی آوازیںآسانی سے سُنائی دینے لگیں گی.ہم جس صدی کے جس سال کی کوئی بات سننا چاہیں گے اُس صدی کے اُس سال پر اُس آلہ کو نصب کر دیں گے اور آوازوں کو سُننا شروع کر دیں گے کاش دنیا اس ترقی سے صداقت کی طر ف آئے.فَذُوْقُوْا فَلَنْ نَّزِيْدَكُمْ اِلَّا عَذَابًاؒ۰۰۳۱ پس (اپنے اپنے اعمال کے مطابق) عذاب چکھو.اور ہم تم کو (عذاب کے بعد) ٭ عذاب ہی دیتے چلے جائیں گے.حل لغات.اَلْعَذَابُ: اَلْعَذَابُ کُّلُّ مَاشَقَّ عَلیَ الْاِنْسَانِ وَمَنَعَہٗ عَنْ مُرَادِہٖ عذاب کے معنے ہیں ہر وہ چیزجو انسان پر شاق گزرے اور حصول مراد سے اُسے روک دے.وَفِیْ الْکُلِّیَاتِ کُلُّ عَذَابٍ فِیْ الْقُراٰنِ فَہُوَا لتَّعْذِیْبُ اِلَّا وَلْیَشْھَدْ عَذَابَھُمَاطَائِفَۃٌ فَاِنَّ الْمُرَادَالضَّرْبُ اور کلیات میں لکھا کہ لفظ عَذَاب سے ٭ یہ مراد نہیں کہ عذاب بڑھتا چلا جائے گا بلکہ مرادیہ ہے کہ جب ایک قسم کا عذاب ختم ہوگا تو پھر دوسرا عذاب شروع ہو جائے گا یعنی جب تک کامل بخشش نہ ہوگی عذاب میں وقفہ نہ ہوگا اس مضمون کو ادا کرنے کے لئے ہم نے اوپر کا ترجمہ کیا ہے.
Page 68
سے مراد قرآن مجید میں ’’عذاب دینا‘‘ ہوتا ہے سوائے وَلْیَشْھَدْ عَذَابَھُمَا کی آیت کے وہاں ظاہری سزا مراد ہے.(اقرب) اَلْعَذَابُ ھُوَالْاِیْجَاعُ الشَّدِیْدُ.عذاب کے معنے ہیں سخت تکلیف دینا.فَالتَّعْذِیْبُ فِیْ الْاَصْلِ ھُوَ حَمْلُ الْاِنْسَانِ اَنْ یَّعْذِبَ اَیْ یَجُوْعَ وَیَسْھَرَ یعنی اگر مادہ کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اُس کے معنے ہیںکسی کو بھوکا اور بیدار رکھنا.کیونکہ عَذَبَ الرَّجُلُ کے معنے ہیں.اُس نے کھانا پینا ترک کر دیا.وَقِیْلَ اَصْلُہٗ مِنَ الْعَذْبِ: فَعَذَّبْتُہٗ اَیْ اَ زَلْتُ عَذْبَ حَیٰوتِہٖ بعض نے کہا ہے کہ عذَاب عَذْبٌ سے نکلا ہے.جس کے معنے میٹھے پانی کے ہیں اور تَعْذِیْب کے معنےاور عذّب کے معنے ہیں کہ اُسے زندگی کی حلاوت سے محروم کر دیا (مفردات) پس عَذَاب کے معنے ہوئے (۱) تکلیف (۲) ایسی چیز جو زندگی کی حلاوت سے محروم کر دے.(۳)جو مقصود حیات سے محروم کر دے.تفسیر.مقہور قوموں کا دنیا میں یہی نقشہ ہوتا ہے جو اس آیت میں کھینچا گیا ہے.اس کا مطلب یہ نہیں کہ عذاب اُن سے ٹلے گا نہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ مقہور قومیں جب اپنی آزادی کے لئے کوشش کرتی ہیںتو وہ اور زیادہ عذاب میں مبتلا ہو جاتی ہیںاور جب تک اُن کے غلبہ کا زمانہ نہیں آتاان کی ہر کوشش اپنے مقصد سے اور زیادہ دور کر دیتی ہے یہی وجہ ہے کہ اس جنگ میں انگریز بار بار بلجیم اور فرانس والوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم جلدی اُٹھنے کی کوشش نہ کرو.اگر تم جلدی اُٹھنے کی کوشش کرو گے تو اَور زیادہ مصیبت میں مبتلا ہو جائو گے چنانچہ جب بھی وہ اپنی آزادی کے لئے کوشش کرتے ہیں جرمن انہیں اور زیادہ تکلیفیں دینی شروع کر دیتے ہیں.فَذُوْقُوْا فَلَنْ نَّزِيْدَكُمْ میں اسلام کے دشمنوں کی ناکامی کی طرف اشارہ پس فَذُوْقُوْا فَلَنْ نَّزِیْدَکُمْ اِلَّا عَذَابًا کا یہ مطلب ہے کہ جب تک اسلام کے غلبہ کا زمانہ ہے تمہاری کوششیں بیکار ہیں جب تک خاموشی سے بیٹھے رہو گے بیٹھے رہو گےلیکن جب تہوّر سے کام لے کر مسلمانوں کے مقابلہ میں اُٹھو گے اُس وقت تم اپنا ہی نقصان کرو گے اسلام اور مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکو گے.قیامت کے لحاظ سے بھی یہ معنی ٹھیک ہیں.انسان پر جوں جوں زمانہ گزرتا جاتا ہے اس کی تکلیف بڑھتی جاتی ہے پہلے دن بخار کی حالت اَور ہوتی ہے دوسرے دن اَور.اور جب بخار لمبا ہو جائے تو مریض کی بالکل اورحالت ہو جاتی ہے.پس عذاب کا زمانہ جتنا لمبا ہوتا چلا جائے گا اُن کی تعذیب بھی بڑھتی چلی جائے گی.پس اس آیت سے یہ مراد نہیں کہ اُن کی نجات نہیں ہو گی بلکہ مراد یہ ہے کہ عذاب کے وقت وہ عذاب میں ہی
Page 69
ترقی کریں گے جوں جوں مرض بڑھتی ہے تکلیف بھی بڑھتی جاتی ہے اور ضعف بھی زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے لیکن اس کے خلاف کبھی عذاب برداشت کرنے کی عادت بھی بڑھ جاتی ہے مگر اُس کا علاج اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ بتا دیاکہ جب اُنہیں عذاب کی عادت ہو جائے گی تو اُن کو نئی جلود دے دی جائیں گی.فَذُوْقُوْا فَلَنْ نَّزِیْدَکُمْ اِلَّا عَذَابًا کے دنیوی لحاظ سے یہ معنے ہوں گے کہ مسلمان روز بروز ترقی کرتے چلے جائیں گےاور جوں جوں وہ ترقی کریں گے کفّار و مشرکین اُن کے مقابلہ میں روز بروز دبتے چلے جائیں گے.اِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ مَفَازًاۙ۰۰۳۲ یقیناً متقیوں کے لئے کامیابی مقدّر ہے.حل لغات.مَفَازٌ مَفَازٌفَازَ کا مصدر بھی ہو سکتا ہے اورظرف مکان کا صیغہ بھی.اور فَازَ (یَفُوْزُفَوْزًا) کے دو معنے ہوتے ہیں.ایک فَازَ مِنْ مَکْرُوْہٍ اور ایک فَازَ بِخَیْرٍ فَازَ مِنْ مَّکْرُوْہٍ کے معنے ہوتے ہیں نَجَا یعنی وہ بُری بات سے بچ گیا اور فَازَ بِخَیْرٍ کے معنے ہوتے ہیں ظَفَرَ بِہٖ اچھی بات اس کو حاصل ہو گئی.(اقرب) مفردات میں ہے اَلْفَوْزُ: اَلظَّفَرُ بِالْخَیْرِ مَعَ حُصُوْلِ السَّلَامَۃِ.یعنی کسی کا بہترین مقصود کو اس طور پر پالینا کہ وہ ہر قسم کے نقصان سے بھی محفوظ رہے فَوْز کہلاتا ہے.(مفردات) پس اِنَّ لِلْمُتَّقِیْنَ مَفَازًاکے معنے ہوئے (۱)کہ متقیوںکو کامیابی حاصل ہو گی یعنی وہ تمام قسم کی بھلائیوں کو پالیں گے اور تمام مصائب سے اُن کونجات مل جائے گی (۲)یہ کہ متقیوں کو یقیناً خدا ایک ایسامقام عطا فرمانے والا ہے جہاں وہ مصائب سے نجات پا جائیں گے اور تمام قسم کی برکات اور کامیابیوں کو حاصل کرلیں گے.ایک مقام تو اُخروی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وعدہ ہے کہ اس مقام میں نہ کسی قسم کا شر ہے اور نہ وہاں خیر کی کوئی کمی ہے بلکہ لَھُمْ مَا یَشَائُ وْنَ (الشوریٰ:۲۳)یعنی جو کچھ وہ چاہیں گے اس میں اُن کو حاصل ہو جائے گے.پس ایک تو وہ مقام ہے جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے یعنی بعث بعد الموت والی زندگی.ددسرے اس دنیا میں بھی مومنوں سے یہ وعدہ ہوتا ہے وَ لِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتٰنِ (الرحمٰن :۴۷)کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے مقام سے ڈرتا ہے اُس کے لئے اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ جنت کے سامان پیدا کر دیتا ہے اور اگلے جہان میں بھی وہ اس کے لئے جنت کے سامان پیدا کرے گا.تفسیر.اِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ مَفَازًامیں مسلمانوں کو مصائب سے نجات ملنے کی پیشگوئی مَیں
Page 70
بتا چکا ہوں کہ اس سورۃ میں غلبۂ اسلام کا بھی ذکر ہے اور قرآن کریم کے غلبہ کا بھی اس میں ذکر ہے پس اس میں پیشگوئی کی گئی ہے کہ مومنوں کے لئے مکروہات سے نجات حاصل کرنے کے سامان پیدا ہو جائیں گے اور ان کوایسی جگہیں عنایت ہو ں گی جو مقام نجات یا مقام کامیابی کہلانے کی مستحق ہوں گی.یہ پیشگوئی ایسے وقت کی گئی تھی جب مسلمانوں کے لئے کسی قسم کا ٹھکانہ نہیں تھا.جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے یہ سورۃ مکّی ہے اور مکّی بھی ابتدائی زمانہ کی ہے.اُس وقت اسلام میں صرف دس بارہ آدمی شامل تھے اور ان کو کفار کی طرف سے ایسی ایسی تکالیف دی جاتی تھیں جن کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے.مکہ میں مسلمانوں پر تکالیف کا زمانہ تاریخ سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ غلام جو ابتدائی زمانہ میں مسلمان ہوگئے تھے کفّار مکّہ اُن کو تپتی ریت پر عرب جیسے گرم علاقہ میں لٹا دیتے اور جب اس کے نتیجہ میں بھی وہ اسلام سے بیزاری کا اظہار نہ کرتے تو تپتے ہوئے پتھر اُن کے سینہ پر رکھ دیتے بلکہ بعض دفعہ کوئی آدمی اُن کے سینہ پر چڑھ جاتا.پھر بعض کے پاؤں میں رسی باندھ کر انہیں مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا.وہاں عام طور پر بارشوں کے اثر سے اپنے مکانات کوبچانے کے لئے دروازوں کے آگے بڑے بڑے پتھر رکھ دیتے تھے.جن کو کھنگر کہتے ہیں تاکہ بارش کی وجہ سے دیواریں خراب نہ ہوں.کفّار مکہ کی عادت تھی کہ وہ مسلمانوں کو جب دکھ دیتے اور اُن کی ٹانگوں میں رسی باندھ کر مکّہ کی گلیوں میں گھسیٹتے تو ان کھنگروں پر سے بھی اُن کو گھسیٹتے ہوئے چلے جاتے اور اُن کے جسم لہو لہان ہو جاتے.ایک صحابی خباب بن ارتّ نے جو پہلے غلام تھے اور غلامی کی حالت میں اسلام قبول کرنے کی وجہ سے اُنہیں بڑی بڑی تکالیف دی گئی تھیں ایک دفعہ فتوحات کے زمانہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اُن سے مشرکوں کی ایذادہی کے متعلق دریافت کیا تب انہوں نے اپنی پیٹھ سے کپڑا اُٹھایا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ان کی پیٹھ کی کھال ایسی تھی جو عام انسانوں کی نہیں ہوتی.وہ دیکھ کر حیران ہوئے اور کہنے لگے کیا آپ کو یہ کوئی بیماری ہے؟ وہ کہنے لگے بیماری نہیں بلکہ پتھروں پر ہمیں گھسیٹا جاتا تھا اس کی وجہ سے زخم اور خراش ہو ہو کر میری پیٹھ کا چمڑا ایسا ہوگیا.(اسدالغابہ فی معرفۃ الصحابۃ زیر عنوان خباب بن الارثؓ الطبقات الکبریٰ زیر عنوان بلال بن رباح ، السیرۃ الحلبیۃ زیر عنوان استخفائہ و اصحابہ فی دار الارقم بن الارقم ،الکامل فی التاریخ لابن اثیر زیر عنوان تاریخ الرسل والانبیاء) یہ حالات تھے جو مسلمانوں پر وارد ہورہے تھے اُدھر رسول کریم صلے اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کی یہ حالت تھی کہ آپؐ باہر نکل کر نماز بھی نہیں پڑھ سکتے تھے.حضرت اُم ہانی ؓ کے مکان میں آپ چند ساتھیوں کو لے کر جمع ہو تے.نماز
Page 71
پڑھتے اور دین کی باتیں کرتے.کھلے میدان میں آپ کا نمازیں پڑھنا یا دین کی باتیں کرنا بالکل نا ممکن تھا.اسی طرح قرآن کریم کو باہر نکل کر پڑھنا یا اپنے صحن میں ہی بلند آواز سے پڑھنا.یہ بھی جُرم سمجھا جاتا تھا جب مصائب حد سے بڑھ گئے تو رسول کریم صلے اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کے صحابہ ؓ آپ سے اجازت لے کر مکّہ مکرمہ سے باہر جانے شروع ہو گئے.(الطبقات الکبریٰ لابن سعد اذن رسول اللہ للمسلمین فی الھجرۃ الی المدنیۃ)ایک دفعہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی ہجرت کا ارادہ کیا.وہ اپنا سامان لے کر جارہے تھے کہ مکّہ کا ایک رئیس ابن الدغنہ انہیں ملا.اُس نے آپ سے پوچھا کہ آپ اسباب باندھ کر کہاں جارہے ہیں؟ اُنہوں نے کہا کہ چونکہ اس جگہ دین کی آزادی نہیں ہے اور میری قوم دشمنی کرتی ہے اس لئے میں مکّہ چھوڑ کر جارہا ہوں.اُس نے کہا وہ شہر کس طرح آباد رہ سکتا ہے جس میں سے آپ جیسا آدمی نکل جائے.میں آپ کا ضامن ہوں آپ باہر نہ جائیں.چنانچہ اُس نے اعلان کر دیا کہ (حضرت) ابو بکر ؓمیری حفاظت میں ہیں.اہل عرب میں بہت بڑی خود سری پائی جاتی تھی لیکن اس کے باوجود ان میں یہ خوبی تھی کہ جب کوئی شخص کسی دوسرے کو اپنی حفاظت اور پناہ میں لے لیتا تو پھر اُسے کوئی شخص تکلیف نہیں پہنچا سکتا تھا اور اگر کوئی پہنچانا چاہتا تودُوسرے اُسے روک دیتے کہ تم ایسا مت کرو یہ فلاں شخص کی حفاظت میں ہے.اُس نے بھی جب اعلان کر دیا کہ ابو بکرؓ میری حفاظت میں ہے تو حضرت ابو بکر ؓ اطمینان کے ساتھ مکّہ میں رہنے لگ گئے.ایک روز وہ اپنے صحن میں باہر نکل کر قرآن شریف پڑھ رہے تھے کہ اِ ن پر رقّت غالب آگئی اور اُن کے آنسو بہنے شروع ہو گئے.حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے کَانَ رَجُلًا بَکاَّءً یعنی اُن کو قرآن شریف پڑھتے وقت بہت رقّت آجایا کرتی تھی اور وہ رو پڑتے تھے.اُن کے قرآن شریف پڑھنے کی آواز سُن کر بچے اور عورتیں اردگرد کے گھروں سے نکل کر وہاں جمع ہو جایا کرتی تھیں.بچوں اور عورتوں میں خصوصیت سے یہ بات پائی جاتی ہے کہ جب اُنہیں کوئی نئی چیز نظر آئے تو دیکھنے کے لئے جمع ہو جاتے ہیں.اُن کے لئے بھی قرآن شریف بالکل نیا کلام تھا اور پھرجب کوئی بڑا آدمی رو رہا ہو تو لازمًا دوسروں کو توجہ پیدا ہو جاتی ہے.چنانچہ اُنہوں نے اپنے دروازوں سے لگ کر قرآن شریف سُننا شروع کر دیا.نتیجہ یہ ہوا کہ جب قرآن کریم کی آواز اُن کے کانوں میں پڑی اُدھر حضرت ابو بکر ؓ کی رقّت اور اُن کے گریہ کو دیکھا تو محلہ کی عورتیں بھی متاثر ہونے لگیں اور اس طرح اس محلہ میں جس میں حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ رہتے تھے اسلام کا چرچا شروع ہو گیا اور عورتوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو بڑی اچھی باتیں ہیں.جب اُن کے خاوندوں کو علم ہوا کہ ہماری عورتیں اس طرح متاثر ہو رہی ہیں تو وہ اس رئیس کے پاس گئے جس نے انہیںاپنی حفاظت میں لیا تھا اور کہا کہ آپ نے ابو بکر ؓ کو اپنی حفاظت میں لے کر یہ کیا مصیبت پید اکر دی ہے کہ
Page 72
ہماری عورتیں اور بچے قرآن سے متاثر ہوتے جا رہے ہیں اگر یہی حالت جاری رہی تو تمام محلہ مسلمان ہو جائے گا.پس یا تو اُسے سمجھائیں کہ وہ قرآ ن شریف بلند آواز سے نہ پڑھا کرے اور یا اپنی حفاظت واپس لے لیں.وہ رئیس حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہا کہ آپ اس اس طرح کرتے ہیں جس پر محلہ والے سخت شکوہ کر رہے ہیں اور کہتے کہ اگر یہی طریق جاری رہاتو ہماری عورتیں اوربچے مسلمان ہو جائیں گے اس لئے آپ یہ کام چھوڑ دیں اور اندر بیٹھ کر قرآن شریف پڑھا کریں ورنہ مجھے اپنی حفاظت کو واپس لینا پڑے گا.حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ نے فرمایاکہ آپ اپنی حفاظت بے شک واپس لے لیں میں اللہ اور ا س کے رسول کی حفاظت میں رہنا پسند کرتا ہوں.(صحیح بخاری کتاب بنیان الکعبۃ باب ھجرۃ النبی و اصحابہ الی المدینۃ.تاریخ الخمیس ھجرۃ ابی بکر الی الحبشۃ ) چنانچہ ابن الدغنہ وہاں سے آیا اور اُس نے اپنی حفاظت واپس لینے کا اعلان کر دیا.بعد میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رائے بھی ہجرت کے متعلق بدل گئی اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ جب آپ کو ہجرت کی اجازت ہو اُس وقت مجھے بھی آپ اپنے ساتھ لے چلیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم نے اس امر کو منظور فرما لیا(صحیح بخاری کتاب مناقب الانصار باب ھجرۃ النبی و اصحابہ الی المدینۃ).ان حالات میں مسلمان مکّہ کے اندر اپنی زندگی کے دن بسر کیاکرتے تھے.میں سمجھتا ہوںاگر مکہ والوں کے مظالم کی مثالیں جمع کی جائیں تو وہ سینکڑوں کی تعداد میں نکل آئیں گی جن سے نہ صرف اُن مظالم کا پتہ لگ سکتا ہے جو اہل مکہ مسلمانوں پر کیا کرتے تھے بلکہ لوگوں کو یہ سبق بھی مل سکتا ہے کہ انہیں دین کی خاطر کس طرح قربانیوں سے کام لینا چاہیے.اِنَّ لِلْمُتَّقِیْنَ مَفَازًا کی پیشگوئی کے مطابق مسلمانوں کے لئے ہجرت کا پہلا مقام اس زمانہ میں جب مسلمان انتہائی تکلیف میں اپنی زندگی بسر کر رہے تھے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ لِلْمُتَّقِیْنَ مَفَازًا یقیناً یقیناً جو مسلمان اور مُتقی ہیں اُن کی مکروہات ایک دن دور ہو جائیں گی اور وہ تکلیف دہ باتیں جو آج پیدا ہو رہی ہیںخدا اُن سب کو مٹا دے گا اور وہ جگہیں اُن کو حاصل ہوں گی جہاں مکروہات اُن کے قریب بھی نہیں پھٹکیں گی.جہاں کامیابی اُن کے پائوں چومے گی اور جہاں آرام اور آسائش کے دروازے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اُن کے لئے کھول دیئے جائیں گے چنانچہ پہلے خدا نے حبشہ کو مَفَازبنایا.مسلمان وہاں ہجرت کرکےگئے اور اللہ تعالیٰ نے اُن کے لئے ہر قسم کے سامانِ راحت بہم پہنچا دیئے.یہ سورۃ چونکہ ابتدائی مکّی سورتوں میں سے ہے اس لئے حبشہ کی ہجرت سے بھی پہلے کی ہے.حبشہ کی ہجرت ۵ کے نصف میں ہوئی (الکامل فی التاریخ لابن اثیر زیر عنوان ذکر الھجرۃ الی ارض الحبشۃ) اور یہ سورۃ پہلے دو تین سال کی ہے پس اِنَّ لِلْمُتَّقِیْنَ مَفَازًا کے مطابق پہلا مقامِ فوز جو مسلمانوں کے لئے
Page 73
ظاہر ہوا وہ حبشہ ہے.چنانچہ حبشہ میں خدا تعالیٰ کی نصرت اور اس کی تائید کا کیسا زبردست نشان ظاہر ہوا.دشمن نے چاہا کہ حبشہ پہنچ کر بھی مسلمانوں کو مبتلائے آلام کرے اور اُنہیں اس ملک میں بھی آرام اور چین سے نہ رہنے دے.مگر وہ خدا جس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ متّقیوں کو ہر قسم کی مکروہات سے بچا کر ایسے مقام پر لے جائے گا جو اُن کے آرام اورسکون کا موجب ہو گا اُس نے کفّارِ مکّہ کو اپنی اس کوشش میں ناکام کیا اور مسلمان اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق حبشہ میں نہایت آرام اور عزت کے ساتھ رہے.چنانچہ تاریخوں میں آتا ہے جب مسلمان حبشہ کی طرت ہجرت کر کے گئے تو عمرو بن العاص اور مکہ کا ایک اور رئیس عبداللہ ابن ابی ربیعہ دونوں حبشہ گئے.ان کو مکّہ والوں نے اس غرض کے لئے مقرر کیا تھا کہ تم جائو اور حبشہ کے بادشاہ سے یہ عرض کرو کہ یہ لوگ ہمارے بھاگے ہوئے غلام ہیں اگر آپ ان کو پنا ہ دیں گے تو ہمارے تعلقات آپ سے اچھے نہیں رہیں گے.یہ لوگ حبشہ گئے اور اپنے ساتھ وہ بڑے بڑے تحفے بھی لے گئے جو اُن کی قوم کے لوگوں نے بادشاہ اور اُس کے وزراء اور پادریوں وغیرہ کے لئے دئیے تھے اور کہا تھا کہ یہ تحفے بادشاہ کو دینا.یہ وزراء کے سامنے پیش کرنا اور یہ پادریوں وغیرہ کو دینا.چنانچہ یہ لوگ بڑی شان کے ساتھ حبشہ پہنچے اور ہر ایک کے سامنے انہوں نے تحائف پیش کئے پہلے تو بادشاہ نے بڑا اعزاز کیا مگر جب انہوں نے تجویز پیش کی کہ یہ لوگ ہمارے ملک میںسے بھاگے ہوئے ہیں ان کو ہمارے ساتھ واپس بھیج دیا جائے اوراس کی سفارش بادشاہ کے وزراء نے بھی کی.مگر بادشاہ نے کہا.کہ جب تک وہ مسلمانوں کو بلا کر اُن کے حالات دریافت نہ کرلے وہ کسی کو اپنے ملک سے نہیں نکال سکتا.چنانچہ بادشاہ نے مسلمانوں کو بلوایا اور پوچھا کہ آپ لوگوں کے کیا عقائد ہیں؟ تب مسلمانوں کے نمائندہ جعفر بن ابی طالب نے قرآن کریم کی چند آیات پڑھیں جن میں اسلامی عقائد کا ذکر آتا تھا اور یہ بھی کہ مسلمان حضرت مسیح ؑ کے متعلق کیا عقیدہ رکھتے ہیں بادشاہ نے وہ آیات سن کر کہا کہ میں تو ان عقائد میں کوئی بری بات نہیں دیکھتا.دوسرے دن پھر دونوں سردار قریش دربار میں آئے اور کہاکہ اے بادشاہ! یہ مسلمان مسیح کی ہتک کرتے ہیں تب اُس نے مسلمانوں کو طلب کیا اور اُن کا جواب سُننے پر دربار میں اُس نے ایک تنکا اُٹھایا اور اُسے اُٹھا کر کہنے لگا جو کچھ ان لوگوں نے حضرت مسیح ؑکے متعلق بیان کیا ہے مَیں اُس سے ایک تنکے کے برابر بھی مسیح ؑ کو زیادہ نہیں سمجھتا اُن کا وہی رتبہ سمجھتا ہوں جو انہوں نے بیان کیا ہے.اِس پر اُس کے درباری بہت چیں بچیں ہوئے.لیکن بادشاہ نے کہا جب میرا باپ مرا تھا مَیں بچہ رہ گیا تھا.تم لوگوں نے میرے چچا کے ساتھ مل کر چاہا کہ اس حکومت پر قبضہ کر لو.تب خدا نے اپنے فضل سے مجھے طاقت بخشی اور اُس نے تم کو شکست دے کر مجھے اس تخت پر بٹھا دیا.جس خدا نے مجھ کو اس بیکسی کی حالت میں بادشاہت کے تخت پر بٹھا دیا اور
Page 74
میرے دشمنوں کو ناکام ونامراد کیا اُس خدا کی نصرت پر مجھے آج بھی یقین ہے اور آج جب مُجھے اُس نے طاقت بخشی ہے مَیں یہ بے شرمی نہیں کر سکتا کہ اُس کے مظلوم بندوںکی مدد نہ کروں.اگر تم سارے اُس کو برا بھی منائو تب بھی مَیں اُن کو یہاں سے نہیں نکالوں گا.چنانچہ سردارانِ قریش جو تحفے لائے تھے ان کو وہ واپس کر دیئے گئے اور وہ ناکام ونامراد واپس لوٹے (تاریخ خمیس ھجرۃ ابی بکر الی الحبشۃ) غرض اِنَّ لِلْمُتَّقِیْنَ مَفَازًا (یعنی متقیوں کو کامیابی اور نجات کا مقام ملنے والا ہے)کا نہایت ہی شاندار نظارہ صحابہ ؓ نے وہاں دیکھا اور انہوں نے اس خدائی وعدہ کو پورا ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کو ایسی جگہ دے گاجہاں مکروہات سے یہ لوگ نجات پا جائیں گے اور آرام اور راحت کو دیکھیں گے.پھر دوسرا نظار ہ اس کا مدینہ میںنظر آیا جبکہ مسلمان وہاں گئے اور اللہ تعالیٰ نے مدینہ کے لوگوں کی توجہ مسلمانوں کی طرف پھیر دی.ابتداء میں صرف چند لوگ مکہ میں حج کے لئے آئے تھے کہ انہیں رسول کریم صلے اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کی خبر پہنچی اور وہ آ پ پر ایمان لے آئے.دوسرے سال بعض اور لوگ مدینہ کے حاجیوں میں سے ایمان لے آئے.اور انہوں نے رسول کریم صلے اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کی خدمت میں تیسرے سال ایک وفد ۷۲آدمیوں پر مشتمل بھیجا جس نے یہ اقرار کیا کہ مدینہ میں آپؐ پر اور آپ کے ساتھیوں پر اگر کوئی دشمن حملہ کرے گاتو ہم اُس سے لڑیں گے اور آپ کی حفاظت کریں گے.چنانچہ اس معاہد ہ کے مطابق رسول کریم صلے اللہ علیہ وآلہٖ وسلم اور آپ ؐکے صحابہؓ مدینہ میں تشریف لے گئے (السیرۃ النبویۃ لابن ہشام زیر عنوان بدء اسلام الانصار) حبشہ میں جو مسلمان ہجرت کر کے گئے تھے وہ بھی اس دوران میںواپس آ کر مدینہ پہنچ گئے.اسی لئے وہ اصحاب الہجرتَین کہلاتے ہیں یعنی دو ہجرتیں کرنے والے.(بخاری کتاب المغازی باب غزوۃ خیبر) کیونکہ انہوں نے حبشہ کی طرف بھی ہجرت کی اور مدینہ کی طرف بھی.پھر مدینہ کے لوگوں نے جس جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم اور مہاجرین کی حظاظت کی یہ تاریخ کا ایک شاندار ورق ہے اَور قرآن کریم کی اس پیشگوئی کی صداقت کا ایک زبردست ثبوت ہے کہ اِنَّ لِلْمُتَّقِیْنَ مَفَازًا یقیناً ہم متقیوں کو وہ جگہ دیں گے جہاں وہ مکروہات سے بچ جائیں گے اور کامیابیوں کا مونہہ دیکھیں گے.چنانچہ پہلا مَفَازَ اللہ تعالیٰ نے حبشہ کو بنایا اوردوسرا مَفَاز اللہ تعالیٰ نے مدینہ کو بنایا.ابتدائی سالوں کی تمام اسلامی تاریخ اسی آیت کی تشریح ہے.حبشہ کا سفر اور مدینہ کے ابتدائی ایام کی تاریخ سب کی سب اِنَّ لِلْمُتَّقِیْنَ مَفَازًا والی پیشگوئی کے پورا ہونے کا ایک نہایت ہی روشن اور زبردست ثبوت ہے.اِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ مَفَازًا میں کی ہوئی پیشگوئی کے مطابق مسلمانوں کے لئے دوسرا نجات کا مقام دوسرے معنے اِنَّ لِلْمُتَّقِیْنَ مَفَازًا کے یہ ہیں.کہ متقیوں کوہم کامیاب و بامراد کریں گے.یہ معنے بھی
Page 75
مدینہ منوّرہ میں پورے ہوئے.اور پھر صرف مدینہ منوّرہ ہی نہیں بلکہ مدینہ منورہ کے بعد سارا عرب اور پھر ساری وسطی دنیا اس پیشگوئی کی صداقت کا ایک نشان تھی کہ کس کس طرح یہ لوگ با مراد ہوئے اور کس کس طرح انہوں نے کامیابیاں حاصل کیں.ہر قوم جو اُن کے مقابلہ میں اُٹھی اُسے شکست ہوئی.ہرطاقت جو مسلمان سے ٹکرائی وہ ذلیل ہوئی.قیصر وکسریٰ کے خزانے فتح ہوئے اور وہ ان مسلمانوں کو ملے.مدینہ منورہ ایک چھوٹی سی بستی تھی جہاں گھر میں بھی باامن طور پر رہنے کا کوئی سامان نہ تھا.چنانچہ اسی لئے مسلمان یہود سے مختلف معاہدات کرتے رہے تاکہ وہ غداری نہ کریں اور مسلمانوں کے ضعف کا موجب نہ بنیں.مگر وہ چھوٹی سی بستی ایک دن ساری دنیا کا مرکز بن گئی.اگر مدینہ منورہ سے کوئی حکم نکلتا تھا تو ساری دُنیا کانپ اُٹھتی تھی.اور وہ سمجھتی تھی کہ اس حکم کا انکار نہیں کیا جا سکتا.پھر مدینہ منورہ ہی وہ بستی تھی جہاں ایک دن قیصر و کسریٰ کے خزائن آئے اور مسلمانوں میں تقسیم ہوئے یہاں تک کہ اسی مدینہ میں کسریٰ کے سونے کے کنگن ایک صحابی سراقہ بن مالکؓ کے ہاتھوں میں پہنائے گئے.رسول کریم صلے اللہ علیہ وآلہٖ وسلم نے ایک دفعہ ہجرت کے سفر میں اُن سے کہا تھا میں تمہارے ہاتھ میں سونے کے کنگن دیکھتا ہوں.جب کسریٰ کی حکومت تباہ ہوئی اور اُس کے سونے کے کنگن مدینہ میں آئے تو حضرت عمرؓ نے رسول کریم صلے اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کی اس پیشگوئی کو پورا کرنے کے لئے جبری طورپر اس صحابی کے ہاتھ میں سونے کے کنگن ڈالے(الاصابہ فی تمییز الصحابۃ الجزء الثالث ذکر سراقۃ بن مالک ) اب کجا مدینہ منورہ جو ایک چھوٹی سی بستی تھی اور کجا کسریٰ کے سونے کے کنگن جو ایک غریب صحابی کے ہاتھوں میں پہنائے گئے جیسا کہ اوپر بتایا گیا ہے کہ مَفَازَ کا لفظ ہلاکت سے نجات کی جگہ کے معنوں کے رُو سے تو حبشہ اور مدینہ پر صادق آتا ہے لیکن دوسرے معنوں یعنی کامیابی کے معنوں کے رُو سے مدینہ ہی مَفَازثابت ہوا.پس جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایاتھا کہ اِنَّ لِلْمُتَّقِیْنَ مَفَازًا تو اس کے معنے یہ تھے کہ میں تم کو مدینہ منورہ دینے والا ہوں جو مقام فوز ہے اور اس آیت میں گو ہجرت اُولیٰ کی بھی پیشگوئی تھی مگر زیادہ وضاحت اور شان سے ہجرت ثانیہ کی پیشگوئی تھی.ایک یوروپین مصنف مدینہ کی اس حالت کو دیکھ کر ایسا متاثر ہوا ہےکہ وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے تم کچھ کہہ لو محمد صلے اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کو.لیکن میں تو جب یہ بات دیکھتا ہوں کہ مدینہ میں ایک چھوٹی سی مسجد میں جس پر کھجور کی ٹہنیوں کی چھت پڑی ہوئی ہے جب بارش ہوتی ہے تو اس میں سے پانی ٹپک پڑتا ہے نماز پڑھتے ہیں تو اُن لوگوں کے گھٹنے اور ماتھے کیچڑ سے لت پت ہو جاتے ہیں.اُس مسجد میں ننگی زمین پر بیٹھے ہوئے ایسے آدمی جن کے نہ سروں پر ٹوپیاں ہیں نہ اُن کے تن پر پورا لباس ہے دنیا کو فتح کرنے کا مشورہ کر رہے ہیں ا ور وہ اس یقین اور
Page 76
وثوق کے ساتھ یہ باتیں کرتے ہیں کہ گویا دنیا کو فتح کرنا ان کے لئے معمولی بات ہے کیونکہ اُن کے نزدیک یہ خدا کا وعدہ ہے جو کبھی ٹل نہیں سکتا.اور پھر وہ ایسا ہی کر کے دکھا دیتے ہیں.تو اس بات کو دیکھ کر میرا دل یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ مَیں ان کو جھوٹا اور فریبی کہوں تو اِنَّ لِلْمُتَّقِیْنَ مَفَازًا میں جو پیشگوئی کی گئی تھی کہ مسلمانوں کو وہ مقام ملے گا جو ان کی کامیابیوں اور فتوحات کا مرکز ہوگا.پہلے وہ انہیں مکروہات سے نجات دلائے گا اور پھر اُن کو کامیابیوں اور فتوحات سے حصہ دے گا.اس پیشگوئی کا نظارہ مدینہ منورہ سے بڑھ کر اور کہیں نظر نہیں آسکتا.مدینہ منورہ سے بڑھ کر اور کوئی مقام ایسا نظر نہیں آتا جو ایسا مرکز بناہو جیسے مدینہ اسلام کا مرکز بنا.کوئی کہہ سکتا ہے کہ لنڈنؔ اور برلنؔ اور پٹسؔبرگ وغیرہ بھی بڑے بڑے مرکز ہیں ان کے مقابلہ میں مدینہ کی مرکزی حیثیت کس طرح پیش کی جا سکتی ہے مگر وہ کہنے والا یہ نہیں سمجھتا کہ یہ مقامات وہ ہیں جنہیں پہلے سے طاقت حاصل تھی.مگر مدینہ وہ مقام تھا جسے کوئی طاقت حاصل نہیں تھی مگرپھر بھی وہ ساری کامیابیوں کا مرکز بن گیا اور اس زمانہ کی پیشگوئی کے مطابق بنا جب مسلمانوں کے لئے سر چھپانے کی جگہ بھی نہ تھی.حَدَآىِٕقَ وَ اَعْنَابًاۙ۰۰۳۳ (یعنی) باغات اور انگور.حل لغات.حَدَآئِق حَدَآئِقَ حَدِیْقَۃٌ کی جمع ہے اور اَلْحَدِیْقَۃُ کے معنے ہیں اَلْبُسْتَانُ یَکُوْنُ عَلَیْہِ حَائِطٌ وہ باغ جس کے ارد گرد دیوار ہو.(اقرب ) اَعْنَاب اَعْنَابٌ عِنَبٌ کی جمع ہے اور عِنْبٌ کے معنے انگور کے ہوتے ہیں یعنی انگور کے پھل کو عربی زبان میں عِنَبٌ کہتے ہیںاور کَرَمٌ انگور کی بیل کو کہا جاتا ہے لیکن عِنَبٌ انگور کو اس وقت کہا جاتا ہے جبکہ وہ تازہ ہو اگر وہ خشک ہو جائے تو اُسے زَبِیْب کہتے ہیں (اقرب) نیز عِنَبٌ شراب ہو بھی کہتے ہیں (اقرب) کیونکہ عنب سے ہی شراب بنتی ہے.دراصل کسی چیز کا جب کسی دوسری چیز میں کوئی غالب اثر پایا جائے تو اُس کانام بعض دفعہ اُسی کے نام پر رکھ دیتے ہیں.عِنْب سے چونکہ خَمْر بنتی ہے اس لئے عربی زبان میں عِنَب کے ایک معنے خَمَر کے بھی کئے جاتے ہیں.تفسیر.حَدَائِق بدل ہے مَفَازًا کا.لیکن میرے نزدیک یہ بدلِ کُل نہیں بلکہ بدل اشتمال ہے یعنی کچھ
Page 77
جُزئیات اس کی بتائی گئی ہیں.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ متقیوں کو جو مَفَا زًا حاصل ہو گا اس کی کچھ تشریحات ہم تم کو بتاتے ہیں.پہلی بات تو یہ ہے کہ متقیوں کو حَدَائِق یعنی باغات ملیں گے.حَدَائِق حَدَیْقَۃٌ کی جمع ہے اوریہ حدیقے مکہ میں نہیں ہوتے مدینہ میں ہی ہوتے ہیں گویا ان الفاظ کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے مدینہ کا نقشہ کھینچ دیا کیونکہ حَدَائِق مدینہ میں ہوا کرتے ہیں.بعد میں بے شک ساری دنیا ہی مسلمانوں کے لئے حَدِیْقۃ بن گئی.لیکن جہاں تک ظاہری الفاظ کا سوال ہے یہ نقشہ مدینہ پر ہی چسپاں ہوتا ہے.لُغت کے لحاظ سے حَدِیْقۃ اُس باغ کو کہا جاتا ہے جس کے اردگرد دیوار ہو (اقرب) اور مدینہ میں اس کا عام رواج تھا.چنانچہ حدیثوں میں آتا ہے کہ جب رسول کریم صلے اللہ علیہ وآلہٖ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی کہ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حتّٰی تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ (آل عمران:۹۳ ) تو ابوطلحہؓانصاری نے سب سے پہلے اپنا حَدِیْقۃ رسول کریم صلے اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے اَحَبّ الْمَال یہحَدِیْقۃ ہے.(بخاری کتاب التفسیرباب قولہ تعالیٰ لن تنالوا البر حتی...و ترمذی جلد دوم کتاب التفسیر باب من سورۃ ال العمران) حَدَآىِٕقَ وَ اَعْنَابًا کے الفاظ سے مقام نجات کی تعیین اسی طرح حضرت ابوھریرہ ؓ کی ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول کریم صلے اللہ علیہ وآلہٖ وسلم ایک دفعہ بعض اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے.اچانک حضور اُٹھ کر چلے گئے جب آپ کو واپس آنے میں دیر ہوگئی تو میرے دل میں سخت گھبراہٹ پیدا ہوئی کہ رسول کریم صلے اللہ علیہ وآلہٖ وسلم نے اتنی دیر کیوں لگا دی ہے ایسا نہ ہوکہ کسی دشمن نے آپ کو نقصان پہنچایا دیا ہو.چنانچہ میں آپ کی تلاش میں انصار کے ایک حَدِیْقۃکی طرف چلا گیا.معلوم ہوتا ہے رسول کریم صلے اللہ علیہ وآلہٖ وسلم نے اُس حَدِیْقۃ کا پھاٹک بند کر لیا تھا.کیونکہ حضرت ابو ھریرہ کہتے ہیں جب مجھے اس باغ کے اندر جانے کااور کوئی راستہ نہ ملاتو میں اُس کی نالی میں سے اندر داخل ہوا جیسے لُومڑ کسی تنگ جگہ میں سے اندر داخل ہوتا ہے (مسلم کتاب الایمان باب من مات علی التوحید دخل الجنۃ قطعا) غرض حَدَائِق کا رواج مدینہ والوں میں زیادہ تھا.پس اللہ فرماتا ہے کہ اس پیشگوئی کے مطابق جو مقامِ فوز مسلمانوں کو ملنے والا ہے اس کی علامت یہ ہے کہ اس میں حَدَائِق ہوں گے اور اس میں اَعْنَاب ہوں گے.حدائق سے مراد مسلمانوں کی منظم حکومت حَدَائِق کہہ کر بتا یا کہ اُن کا اپنااپنا علاقہ ہو گا اور اُس پر اُنہیں قبضہ تامّہ حاصل ہو گا.کیونکہ حَدِیْقۃ وہی ہوتا ہے جو دوسروں سے الگ ہو.اگر حَدِیْقۃ کے اردگرد دیوار نہ ہو تو یہ شبہ رہتا ہے اِس کی سرحدکون سی ہے اور اُس کی سرحد کون سی ہے.پس جب مومنوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے حَدَائِق
Page 78
کے لفظ کا استعمال فرمایا تو اگر اس سے وہ ساری حکومت مراد لی جائے جو مسلمانو ں کو ملنے والی تھی ا ور یہ سمجھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی آئندہ حکومت کا نام اس جگہ حَدِیْقۃ رکھا ہے تب اس کے یہ معنے ہوں گے کہ مسلمانوں کی حکومت نہایت منظم ہوگی اور اس کی سرحدیں مضبوط ہوں گی جیسے باغ کے اردگرد دیواریں ہوتی ہیں.اور وہ ان دیواروں کی وجہ سے محفوظ ہوتا ہے اسی طرح مسلمانوں کی حکومت منظم ہوگی اور اس کی سرحدیں مضبوط ہوں گی.اسی کے متعلق قرآن کریم نے دوسری جگہ ان الفاظ میں توجہ دلائی ہے یَآاَیُّھَاالَّذِیْنَ اٰمِنُوْااصْبِرُوْاوَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا (آل عمران:۲۰۱) کہ اے ایماندارو صبر سے کام لو.اور دشمن سے بڑھ کر صبر دکھائو اور سرحدوں کی نگرانی رکھو یعنی مسلمان حکومت کو چاہیے کہ وہ اپنی سرحدوں کو مضبوط رکھے اور وہاں حفاظت اور نگرانی کے لئے اپنی فوجوں کو مقرر کرے تا کہ اسلامی علاقہ محفوظ رہے اور غیر اسلامی حکومت کو یہ جرأت نہ ہو کہ وہ اسلامی حکومت پر حملہ کرے.حَدَائِق کے لحاظ سے ہی رسول کریم صلے اللہ علیہ وآلہٖ وسلم نے فرمایا اِنَّ لِکُلِّ مَلِکٍ حَمیً اَلَا وَ اِنَّ حِمَی اللّٰہِ مَحَارِمُہُ کہ ہر بادشاہ کی ایک رَکھ ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رَکھ اُس کے محارم ہیں.آپ نے فرمایا جو شخص بادشاہ کی رکھ کے قریب اپنے جانور کو چراتا ہے وہ بھی غلطی کرتا ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کسی وقت اُس کا جانور با دشاہ کی رَکھ میں چلا جائے اور وہ نقصان اُٹھائے (بخاری کتاب الایمان باب فضل من استبرا لدینہ) پس ایک معنے اس کے یہ ہوں گے کہ مومن اپنے اعمال کی حد بندی کر تا ہےوہ حرام اورحلال میں امتیاز کرتا ہے اور چونکہ متقی کا کام یہ ہوتا ہے کہ حلال اور حرام میں تمیز کرے اس لئے اللہ تعالیٰ نے اپنی ان نعمتوں کا نام جو وہ مومنوں کو دے گا حَدِیْقۃ رکھ دیا.یعنی جس طرح اُس نے فرق کیااور خدا تعالیٰ کی رضا کے لئے حلال اور حرام میں امتیاز روا رکھا اسی طرح خدا مومن اور غیرمومن میں امتیاز کرے گا اور اُسے انعام کے طور پر حَدَائِق عطا فرمائے گا اوراس نسبت سے کہ سچا تقویٰ انسان کے لئے غذا کا بھی کام دیتا ہے اور پھل کا کام بھی دیتا ہے اور نشۂ محبت الٰہی بھی پیدا کرتا ہے اس کا نام اَعْنَاب رکھ دیا کیونکہ اتّقا میں یہ ساری شرطیں ہوتی ہیں.ایک طرف وہ مومن کی روحانی غذا ہوتا ہے جس سے وہ خدا کا قرب حاصل کرتا ہے.دوسرے جسے سچا تقویٰ میسر آجاتا ہے وہ آئندہ ایک لمبے زمانہ تک دنیا میں نیک تبدیلی پیدا کرنے کا موجب بن جاتا ہے جیسے ذخیرہ خور غذا دیر تک رہتی اور انسان کے کام آتی ہے اسی طرح تقویٰ ایک لمبے زمانہ تک دنیا کے کام آتا ہے گویا ایک طرف وہ انسان کو اپنی ذات کے لئے تازہ بتازہ پھل کاکام دیتا ہے اور دوسری طرف آئندہ کے لیے بھی ذخیرہ کا کام دیتا ہے.چنانچہ اسی بناء پر حضرت دائود علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے صادق کو ترک کئے ہوئے اور اس کی نسل میں سے کسی کو ٹکڑے مانگتے نہیں دیکھا (زبور ۳۷ آیت ۲۵) گویااِتقا کیا ہے ایک
Page 79
ذخیرہ خور غذا ہے جو نہ صرف اس کو فائدہ پہنچاتی ہے بلکہ اس کی آئند ہ آنےوالی نسلوں کو بھی فائدہ پہنچاتی ہے پھر تقویٰ محبت الٰہی پیدا کرنے کا بھی موجب ہے جیسے عِنَب میں سے شراب نکلتی ہے اسی طرح تقویٰ کے ذریعہ محبت الٰہی پیدا ہوتی ہے جیسے شراب پی کر انسان مست ہو جاتا ہے اور اُسے کسی خیر وشر کی پروا نہیں رہتی.نہ اسے کسی نقصان سے ڈر آتا ہے اور نہ کسی خیر کے حصول کی خواہش اُس کے دل میں رہتی ہے محض ایک مستی ہوتی ہے جو شراب کی وجہ سے اُس کے دماغ میں پیدا ہو جاتی ہے اور وہ نہ کسی خوف سے کام کرتا ہے اور نہ کسی لالچ سے.ایک رستہ ہوتا ہے جس پر وہ اس نشہ کی حالت میں چل پڑتا ہے.اسی طرح جب کسی شخص کے دل پر محبت الٰہی غالب آجائے تو اس نشہ میں وہ ایسا چور ہو جاتا ہے کہ وہ نہ دوزخ کے ڈر کے مارے خدا سے تعلق رکھتا ہے اور نہ جنت کی لالچ اُسے نیکیوں پر آمادہ کرتی ہے.ڈر اور لالچ کی قسم کے تمام احساسات اُس کے دل سے مٹ جاتے ہیں اور وہ خدا سے محض خدا کی رضا کے لئے محبت کرتا ہے گویاوہ یہ نہیں چاہتا کہ میں دوزخ سے بچ جائوں وہ یہ نہیں چاہتا کہ میں جنت میں داخل ہو جائوں بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے.جنت میں حدائق و اعناب ملنے میں حکمت پس تقویٰ بھی ایک مستی پیدا کر دیتا ہے جیسے اَعْنَاب سے جو خمر تیارہوتی ہے وہ انسان کو مست بنا دیتی ہے.حضرت جنید بغدادی ؒ سے ایک دفعہ سوال کیا گیا کہ آپ جب اللہ تعالیٰ سے ملیں گےتو اُسے کیا کہیں گے انہوں نے کہا کہ میں تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے یہ کہوں گا کہ خدایا مجھے نہ جنت کی خواہش ہے نہ دوزخ کا خوف ہے.مَیں تو یہ چاہتا ہوںکہ تُو مجھے جہاں رکھنا چاہتا ہے وہاں رکھ دے.اگر دوزخ میں ڈالنا چاہتا ہے تو دوزخ میں ڈال دے اور اگر جنت میں لے جانا چاہتا ہے تو جنت میں لے جا.مجھے تو تیری رضا کی ضرورت ہے (تذکرۃ الاولیاء باب چہل و سوم ذکر جنید بغدادی) یہ مستی کی ہی علامت ہے نہ اچھی بات کی خواہش رہے اور نہ بُری بات کا ڈر ہے.ایک ہی غرض سامنے رہے کہ میرا محبوب مجھ سے راضی ہو جائے.غرض اَعْنَابًا کا ذکراس لحاظ سے کیا گیا ہے کہ اَعْنَاب ہی وہ پھل ہے کہ پینے کے کام بھی آتا ہے اور میوہ کے کام بھی آتا ہے اور خشک کرکے غذا کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے.پس اسے خاص طو ر پر قرآ ن کریم نے مثال کے طور پر چُنا ہے یہ بتا نے کے لئے کہ ایمان کی بھی یہی مثال ہوتی ہے کہ وہ بشاشت بھی بخشتا ہے وہ لذت بھی بخشتا ہے اور وہ طاقت بھی بخشتا ہے.اسی طرح یہ تینوں چیزیں تقویٰ میں بھی پائی جاتی ہیں کہ وہ غذا بھی ہے.وہ ذخیرہ خور غذا بھی ہے اور وہ عشق الٰہی بھی پیدا کرتی ہے یعنی خمر والی حالت بھی اس میں پائی جاتی ہے مگر خمر تو انسان کی عقل پر پرد ہ ڈال دیتی ہے یہ وہ نشہ ہے جو عقل کو تیز کرتا ہے.البتہ یہ مشابہت ضرورپائی جاتی ہے کہ جس طرح خمر انسان کو مست بنا دیتی
Page 80
ہے اسی طرح تقویٰ اور ایمان کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کی محبت میں مست ہو جاتا ہے.وَّ كَوَاعِبَ اَتْرَابًاۙ۰۰۳۴ اور ہم عمر نوجوان عورتیں.حل لغات.کَوَاعِب: کَوَاعِبَ کَاعِبَۃٌ کی جمع ہے اور کَاعِبَۃٌ کے معنے ہوتے ہیں اَلنَّاھِدُ جوان لڑکی.(اقرب) اَتْرَابٌ: اَتْرَابٌ تِرْبٌ کی جمع ہے اور تِرْبٌ اس کو کہتے ہیں جو کسی کا ہم عمر ہو.اکثر استعمال اس کا مؤنث میں ہوتا ہے.کہتے ہیں ھَذِہٖ تِرْبُ فُلَانَۃٍ اِذَاکَانَتْ عَلٰی سِنِّھَا (اقرب)یہ فلاں عورت کی تِربْ ہے جبکہ وہ اس عور ت کی ہم عمر ہو.پس کَوَاعِب کے معنے ہوئے.نوجوان عورتیں.اور اَتْرَاب کے معنے ہوئے.ہم عمر عورتیں.کیونکہ عربی زبا ن کے لحاظ سے اَتْرَابًا میں مرد اور عورت کا مقابلہ نہیں ہوتا یعنی یہ مطلب نہیں ہوتا کہ فلاں مرد کے ہم عمر عورت.بلکہ اَتْرَاب کے معنے ہوتے ہیں آپس میں ہم عمر عورتیں یعنی اَتْرَاب میں ہم عمر ہونے کے جو معنے ہیں اُن کی نسبت عورتوں کے لحاظ سے ہے یعنی عورت عورت کی ہم عمر ہو.مردوں اور عورتوں میں یہ نسبت نہیں.چنانچہ تاج العروس میں سیوطی کا قول درج ہے.’’اَلْاَتْرَابُ: اَلْاَسْنَانُ.لَا یُقَالُ اِلَّا لِلْاِنَاثِ وُیُقَالُ لِلذُّکُوْرِ اَلْاَسْنَانُ وَالْاْقْرَانُ وَاَمَّا الِلّدَاتُ فَاِنَّہٗ یَکُوْنُ لِلذُّکُوْرِوَلْاِنَاثِ وَقَدْ اَقَرَّہُ اَئِمَّۃُاللِّسَانِ عَلٰی ذَالِکَ‘‘ (تاج) یعنی عربی زبان میں جب مردوں کی ہم عمری کا ذکر ہو تو اَقْرَان اور اَسْنَان کا ذکر کرتے ہیں.اور جب عورتوں کے آپس میں ہم عمری کا ذکر ہو تو اَتْرَاب کہتے ہیں او ر مؤنث و مذکر دونوں کا ہو تو لِدَات.چنانچہ تما ائمہ لغت اس بات کی تائید کرتے ہیں پس کَوَاعِبَ اَتْرَابًا کے معنے ہوئے آپس میں ہم عمر جوان عورتیں.تفسیر.مومنوں کو کواعب و اتراب ملنے کا مطلب اس آیت میں اس امر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ قوم میں کام کی حقیقی روح تبھی پیدا ہوتی ہے جب ایک حد تک اُن میں خیالات کا اور جوش کا اور ہمت کاتوازن قائم ہو.کسی قوم میں اگربعض لوگ بہت بڑے شاندار کارنامے سر انجام دینے والے ہوں اور باقی لوگ
Page 81
اس معیار کے نہ ہوں تو وہ قوم کبھی کوئی بڑی کامیابی حاصل نہیں کر سکتی.بڑی کامیابی کے حصول کے لئے ضروری ہے کہ قوم کا عام معیارِ اخلاق ایک ہو.اگر قوم کا ایک فرد آسمان پر ہو اور دوسرا زمین پر تو وہ کبھی اپنی قوم کے لئے اتنے مفید ثابت نہیں ہو سکتے جتنے مفید وہ ساٹھ ستر فیصدی افراد ہو سکتے ہیں جو مثلاًایک ایک گز زمین سے اُونچے ہوں کیونکہ گو وہ آسمان والے کے مقابلہ میں بہت نیچے ہوں گے مگر سب کا معیار یکساں ہوگا.اگر دس افراددو دو فٹ بھی اُونچے ہوں تو وہ اُن دس افراد سے زیادہ مفید ہوں گے جن میں سے ایک آسمان پر ہو اور نو زمین پر.پسكَوَاعِبَ اَتْرَابًا میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیاہے کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ایسی برکتیں دے گا کہ جب وہ مقام مفاز میں پہنچیں گے تو ان کی ایک نمایاں خصوصیت یہ ہوگی کہ ان کی عورتوں کا دینی معیا ربھی اُونچا ہو جائے گا اور پھر وہ اس معیار میں ایک دوسری کے برابر ہوں گی.غرض کَوَاعِب میں اُن کے معیار کے اونچا ہونے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے یعنی عورتوں کا دینی معیا ر بلند ہو گااور سب میں جوش اور جوانی اور بلندی پائی جائے گی.اور اَتْرَابٌ سے اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اُن کی ترقی قومی ترقی ہوگی انفرادی نہیں.یعنی سب میں یہ جوش ایک دُوسرے سے ملتا جلتا پایا جائے گا.یہ نہیں ہوگاکہ چند عورتوں میں توجوش وخروش بے انتہاء ہواور باقی اپنے فرض سے غافل ہوں بلکہ سب عورتوں میں ملتا جُلتا دینی جوش پایا جائے گا اور وہ سب کی سب دین کی ترقی کے لئے ایک جیسی قربانی کرنے کے لئے تیار رہیں گی چنانچہ اسلامی تاریخ کا اگر مطالعہ کیا جائے تو کثرت سے ایسی عورتوں کی مثالیں نظر آتی ہیں جنہوں نے جنگوں میں بہت بڑی جرأت اور ہمت کا ثبوت دیا.مہاجرین کی بیویوں کو ہم دیکھتے ہیں تو اُن میں بھی ہمیں یہ شان نظر آتی ہے اور انصار کی بیویوں کو دیکھتےہیںتو اُن میں بھی ہمیں یہ شان نظر آتی ہے.ہزارہا عورتیں ایسی ہیں جن کا تاریخوں میں ذکر آتا ہے اور جنہوں نے مختلف مواقع پر كَوَاعِبَ اَتْرَابًا ہونے کی ایسی شان دکھائی کہ آجکل کے مرد بھی اُن کے مقابلہ میں ہیچ نظر آتے ہیں.اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کَوَاعِب کا لفظ استعمال فرمایا ہے جو جسمانی اور روحانی دونوں حالتوں پر دلالت کرتا ہے مگر ایسے لفظ کے لانے میں حکمت یہ تھی کہ یہاں وہ مضمون بیان کئے جارہے تھے ایک وہ مضمون تھا جس کا قیامت سے تعلق تھا اور ایک وہ مضمون تھا جس کا اس دنیا سے تعلق تھا.اس لئے اللہ تعالیٰ نے ایسا لفظ استعمال فرمایا جو دونوں مقامات پر چسپاں ہو سکتا ہے قیامت کے معنے اگر لئے جائیں تب بھی یہ لفظ ٹھیک ہے کیونکہ جنت میں ہر آدمی جوان ہونے کی حالت میں داخل کیا جائے گا.حدیثوں میں آتا ہے رسول کریم صلے اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کے پاس ایک دفعہ ایک بوڑھی عورت آئی.معلوم ہوتا ہے اُسے بے وقت بات کرنے کی عادت تھی اُس نے آتے ہی
Page 82
آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میرے لئے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کرے آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم غالباً اور گفتگو میں مصروف تھے اِس لئے اُسے مذاقًا مختصر طور پرجو اب دیا کہ جنت میں کوئی بوڑھی عورت نہیں جائے گی.وہ یہ سنتے ہی رونے اور چیخنے چِلّانے لگی اور اسی حالت میں واپس ہو گئی.آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم نے صحابہ ؓمیں سے کسی کو بُلا کر فرمایا کہ جائو اس کو کہو میرا وہ مطلب نہیں تھا جو اُس نے سمجھا ہے بلکہ میرا مطلب تو یہ تھا کہ جنت میں جو بھی داخل کئے جائیں گے سب جوان ہو کر جائیں گے بڑھاپے کی حالت میں نہیں جائیں گے.(شمائل ترمذی باب ما جاء فی صفۃ مزاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) کواعب اور اتراب سے مراد مسلمان عورتیں اور واقعہ میں وہ مقام جو دائمی سرور کا ہے وہاں اگر بڑھاپے کی حالت میں کوئی شخص چلا جائے تو جنت دوزخ سے بد تر بن جائے.آدمی تو ساٹھ اسی سو سال تک بوڑھا ہو جاتا ہے اگر اسی طرح اس کا بڑھاپا بڑھتا چلا جائے تو دس بیس ہزار سال میںتو وہ ایسی ذلیل چیز بن جائے گا کہ اس کا لذت اٹھا نا تو الگ رہا.وہ شاید ایک گیند کی شکل میں تبدیل ہوجائے گا.پس جنت کی یہ ایک ضروری شرط ہے کہ وہاں سب جوان کر کے داخل کئے جائیںگے اور ہمیشہ اسی حالت میں رکھے جائیں گے.اسی طرح جنت کے لحاظ سے انسان کے جو ساتھی ہوں گے یعنی بیوی بچے وہ بھی سب جوان ہوں گے لیکن جب ہم اس آیت کو دنیا پر چسپاں کریں تو پھر کَوَاعِب کے معنے ایسی ہی عورتوں کے ہوں گے جو حوصلہ اور جرأت اور بہادری کے لحاظ سے جوان ہوں.کَوَاعِب کے یہ معنے نہیں ہوں گے کہ وہ جسمانی لحاظ سے جوان ہوںگی کیونکہ اگر یہ معنے لئے جائیں تو پھر اِنَّ لِلْمُتَّقِیْنَ کَوَاعِبَ کے یہ معنے ہوں گے کہ اِنَّ لِلْمُتَّقِیْنَ کَوَاعِبَ فِیْ الْاِبْتِدَائِ یعنی متقیوںکو شروع میں جوان بیویاں ملیں گی لیکن بعد میں بوڑھی ہو جائیںگی اور یا پھر یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ متقیوں کا فرض ہے کہ وہ جوان عورتوں سے شادیاں کریں اور جب وہ بوڑھی ہونے لگیں تو انہیں طلاق دے دیا کریں کیونکہ اُس وقت وہ کَوَاعِب نہیں رہ سکتیں اور یا پھر یہ ماننا پڑے گا کہ متقیوں کو جو عورتیں ملیںگی وہ کبھی بوڑھی ہی نہیں ہوں گی مگر یہ تینوں صورتیں غلط ہیںاور انسان کو مجبور کرتی ہیں کہ اس جگہ روحانی معنے مراد لے جسمانی معنے مرادنہ لے کیونکہ یہاں زمانہ نہیں بتایا گیا کہ وہ فلاں عمر میں جوان ہوں گی اور فلاں عمر میں نہیں بلکہ بتا یا یہ گیا ہےکہ وہ ہمیشہ کَوَاعِب رہیں گی.پس لازمًااس کے معنے جوان عمرہونے کے نہیں بلکہ حوصلہ اور ہمت کے لحاظ سے جوان ہونے کے ہیں.پھر بتایا کہ وہ نہ صرف ہمت اور عزم اور ارادہ کے لحاظ سے جوان ہوںگی بلکہ وہ اَتْرَاب بھی ہوںگی یعنی ساری عورتیں یکساں جوان ہوں گی.ساری عورتیں یکساں بلند ہمت ہوں گی اور ساری عورتیں یکساں حوصلہ مند ہوں گی.یہ ایک بہترین انعام
Page 83
ہے جو کسی قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے کہ جیسے اُس قوم کے مردوں میں جوش ہو ویسا ہی اُس قوم کی عورتوں میں جو ش ہو.جیسی چند عورتیں بہادر اور دلیر اور قوم کیلئے قربانی کا مادہ اپنے اندر رکھنے والی ہوں ویسی ہی تمام عورتیں بہادر اور دلیر اور قربانی کا مادہ رکھنے والی ہوں بلکہ ایک سے ایک بڑھ کر ہو.یہ حقیقی انعام ہے جس سے قومیں ترقی کیا کرتی ہیں.دنیا میں انسان کو بُزدلی کی طرف لے جانے والی عورت ہی ہوتی ہے مرد دین کے لئے باہر جانا چاہتا ہے تو عورت اس کے سامنے کھڑی ہوجاتی ہے اور کہتی ہے تم مجھے کہاں چھوڑے جارہے ہو تمہارے بغیر میرا کون سہارا ہے.پھر کبھی وہ بچوں کو اس کے سامنے لاتی ہے اور کہتی ہے اِن بچوں کو کون پوچھے گا.اس پر مرد کا دل بھی بے چین ہو جاتا ہے اور اس کے ارادہ میں تذلزل پیدا ہوجاتا ہےلیکن جب عورت اس کی ہمت بندھاتی ہے جب وہ اسے جرأت اور دلیری کا سبق دیتی ہے.جب وہ کہتی ہے کہ شاباش جائو اور خدا کے دین کا کام کرو تو مرد کا دل بڑھ جاتا ہے اور وہ پوری بے فکری سے دینی ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں مشغول ہو جاتا ہے.پس ضروری ہے کہ عورتیں دینی لحاظ سے بلند معیار پر قائم ہوں اور سب میں دین کا یکساں جوش اور قربانی کی یکساں روح پائی جاتی ہو.مسلمانوں کی عورتوں کے کواعب و اتراب ہونے کے ثبوت اس جرأت اوربہادری کا نمونہ جن عورتوں نے دکھایا ان کی مثالوں سے اسلامی تاریخ بھری پڑی ہے.انہوں نے اسی رُوح سے کام لیتے ہوئے بعض دفعہ اپنے مردوں سے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر تم میدان جنگ سے بھاگوگے تو پھر ہمارے پاس نہ آنا.تاریخوں میں آتا ہے کہ جب جنگ یرموک میں یک دم عیسائی لشکر نے کثیر تعداد اور بھاری سامان کے ساتھ حملہ کیا تو اسلامی لشکر مقابلہ کی تاب نہ لا کر وقتی طور پر پیچھے ہٹنے پر مجبور ہوا.اُس وقت مسلمان عورتوں نے خیمے توڑ کر اُن کی لکـڑیاں ہاتھوں میں سنبھال لیں اور مسلمان سپاہیوں کے گھوڑوں کے مونہوں پر مار مار کر ان کو واپس دشمن کے لشکر کی طرف لوٹا دیا.ان عورتوں میں سے ایک ہند بنت عتبہ بن ربیعہ بھی تھی جو کسی زمانہ میں اسلام کی شدید ترین دشمن رہ چکی تھی.مسلمان پیچھے ہٹنے والے سپاہیوں میں ا بو سفیان اس کا خاوند بھی شامل تھا اور معاویہ اس کا بیٹا بھی.چنانچہ جب لشکر بھاگتا ہوا واپس پہنچا تو ابو سفیان جو لشکر کے اس حصہ کا سردار تھا اُس کی بیوی ہند نے اس کے گھوڑے کو خیمے کی لکڑی سے مار کر واپس کیا اور کہا کہ آنحضرت صلے اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کی مخالفت میںتو پیش پیش ہوتا تھا اب اسلام قبول کر کے میدان جنگ سے کیوں بھاگتا ہے.تمہار ا تو یہ فرض ہو نا چاہیے کہ تم نے اسلام کی شرک کی حالت میں مخالفت کی تھی اس کو دھو ڈالو اور اپنی جان پر کھیل جائو.چنانچہ اُس نے اور باقی سپاہیوں نے جب یہ نظارہ دیکھا تو کہا کہ واپس لوٹو.دشمن کی تلواروں سے مسلمان عورتوں کے ڈنڈے زیادہ سخت ہیں.یہ سُن کر لشکر واپس لوٹا اور آخر
Page 84
دشمن پر فتح پائی.(فتوح الشام للواقدی وقعۃ الیرموک تحریض النساء للمسلمین علی القتال) پس كَوَاعِبَ اَتْرَابًاکے مطابق اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلے اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کو عورتوں کاایسا لشکر دیا جو دوسری قوموں کے مردوںسے بھی بالا تھا اور پھر ان عورتوں میں سے بھی ایک سے ایک بڑھ کر تھی.یہ نہیں کہ حضرت عائشہ ؓ تو بہادر ہوں اور حضرت زینب ؓ نہ ہوں یا حضرت زینب تو بہادر ہوں مگر اسماء بنت ابی بکرؓ بہادر نہ ہوں بلکہ حضرت عائشہ ؓ بھی کَوَاعِبَ اَتْرَابًا کا مصداق تھیں اور حضرت زینب ؓبھی کَوَاعِبَ اَتْرَابًا کامصداق تھیں اور اسماء بنت ابی بکرکَوَاعِبَ اَتْرَابًا کا مصداق تھیں بلکہ ہم تو دیکھتے ہیں ہند جیسی عورت جو کسی زمانہ میں شدیددشمنِ اسلام رہ چکی تھی اس میں بھی یہ روح کام کر رہی تھی اور انہوں نے ایسی قربانیاں کیںجن کی کوئی حد ہی نہیں.اسی جنگ کا یہ واقعہ ہے کہ عیسائی لشکر کی طرف سے جب مسلمانوں پر بہت زیادہ دبائو پڑاتو مقابلہ کرتے کرتے اسلامی لشکر بالکل تھک گیا.ایک رات اسلامی لشکر کے کمانڈر انچیف جو حضرت ابو عبیدہ تھے چکّر لگانے کے لئے نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ اسلامی لشکر کے اردگرد دو آدمی پھر رہے ہیں اُنہیں شبہ پیدا ہوا کہ دشمن کے آدمی جاسوس کے طور پر نہ آئے ہوںچنانچہ وہ آگے بڑھے اور انہوں نے آواز دی کہ تم کون ہو!اس پر حضرت زبیر ؓ آگے بڑھے اُن کے ساتھ اُن کی بیوی اسماء بنت ابی بکر بھی تھیں.انہوں نے کہا کہ آج مسلمان چونکہ سخت تھکے ہوئے تھے اس لئے میں اور میری بیوی دونوں پہرہ کے لئے نکل کھڑے ہوئے (فتوح الشام للواقدی.وقعۃ الیرموک ھزیمۃ الروم ) یہ کَوَاعِبَ اَتْرَابًا کی کیسی شاندار مثال ہے اور کس طرح ان مثالوں سے ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ ؓ کی عورتوں میں بھی وہی جزبۂ فدا کاری پایا جاتا تھا جو خود صحابہ کے اندر موجود تھا.پھر یہ نہیں کہ یہ جز بہ کسی خاص خاندان کی عورتوں سے مخصوص ہو بلکہ ہر عورت اسی جزبہ سے سرشار تھی اور یہی روح اُس میں کام کرتی دکھائی دیتی تھی ورنہ دنیا کے لحاظ سے کَوَاعِب کے کوئی اور معنے بنتے ہی نہیں.جوان لڑکی پانچ سات سال میں ہی جوانی کی عمر گزار دیتی ہے اور پھروہ کَوَاعِب میں شامل نہیں رہتی.مگر یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ متقیوں کو ایسی عورتیں ملیں گی جو کَوَاعِب ہی رہیں گی.اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہاں روحانی معنے مراد ہیںجسمانی نہیں.بے شک اگلے جہان کے لحاظ سے جسمانی معنے ہی ٹھیک ہیں کیونکہ جنت میں اگر بوڑھے داخل ہوں یا بڑھاپا آ جائے تو پھر جنت جنت نہیں رہتی.لیکن جب ہم اس آیت کو دنیا پر چسپاں کریں گے تو اس کے معنے ایسی عورتوں کے ہوں گے جو جوانی والی طاقتیںا پنے اندر رکھتی ہوںکیونکہ دنیا میں انسانی جسم بہرحال نڈھال ہو جاتا ہے.اور عمر کی زیادتی کے ساتھ بڑھاپے کے آثار ظاہر ہونے شروع ہو جاتے ہیں.لیکن روحانی طاقتیں اگر انسان ان کو ترقی دینا چاہے تو کمز ور نہیں ہو سکتیں.
Page 85
پس بڑی بات یہ ہے کہ قوم کی عورتیںکَوَاعِبَ اَتْرَابًا کی مصداق ہوں.کواعب کے لفظ سے مسلمان عورتوں کی ذاتی جوانی اور لفظ اتراب سے قومی جوانی کی طرف اشارہ کَوَاعِب کا لفظ ذاتی جوانی پر دلالت کرتا ہے اَور اَتْرَاب کا لفظ قومی جوانی پر دلالت کرتا ہے.اَتْرَاب کا لفظ بھی بتا رہا ہے کہ اس جگہ روحانی معنے ہی زیادہ موزون ہیں کیونکہ جنّت کے متعلق اَتْرَاب کے لفظ میں کوئی حکمت نہیںہو سکتی.یہ لفظ دنیا سے ہی تعلق رکھتا ہے اور بتاتا ہے کہ وہی قوم ترقی کر سکتی ہے جس کی ساری عورتوں کا دینی معیاربلند ہو.وہ جواں ہمت اور حوصلہ مند ہوں.وہ مصائب اور مشکلات کی پرواہ کرنے والی نہ ہوں.وہ دین کے لئے ہر قسم کی قربانی پر تیار رہنے والی ہوںوہ جرأت اور بہادری کی پیکر ہوں اور وہ اپنے اخلاص اور اپنے جوش اور اپنی محبت میں مردوںسے پیچھے نہ ہوں.یہ معنے ایسے لطیف ہیں کہ میرے نزدیک اپنی ذات میں اس بات کے مستحق ہیںکہ ان معنوں کو بار بار بیان کیا جائے.ان پر زور دیا جائے اور انہیں اپنی تقریر وتحریر میں بتکرار لایاجائے تا کہ معلوم ہو کہ اسلام عورتوں کو کس بلند مقام پر پہنچانا چاہتا ہے اور عورتوں میں بھی دینی روح ترقی کرے.اگلے جہان میں اگر ساری عورتیں ایک ہی عمر کی ہوں تو اس میں کوئی خاص لطف کی بات نہیں.وہ غرض کَوَاعِب کہہ کر ہی پوری ہو سکتی تھی.اَتْرَاب کا لفط زائد طور پر لانا بتا رہا ہے کہ یہ بات خصوصیت سے اس دنیا سے تعلق رکھنے والی ہے.وَّ كَاْسًا دِهَاقًاؕ۰۰۳۵ اور چھلکتے ہوئے پیالے.حل لغات.اَلْکَاْسُ: اَلْاِنَاءُ یُشْرَبُ فِیْہِ.وہ برتن جس میں کوئی چیز پی جاتی ہے.وَقِیْلَ مَادَامَ الشَّرَابُ فِیْہِ وَاِلَّا فَھِیَ زُجَاجَۃٌ وَاِنَاءُ وَقَدْحٌ اور بعض کہتے ہیں کہتے ہیں کہکَاْسٌ پینے کے برتن کو اس وقت کہیں گے جبکہ اس میں پینے کی چیز بھی موجود ہووگرنہ خالی برتن عربی زُبان میں زُجَاجَۃ اور اِنَاء اور قَدْح کہلاتا ہے.لفظ کَاْسٌ مؤنث ہے.(اقرب) دِھَاق دھاق کا لفظ جب کَاْس کے لئے آئے تو اس کے معنے بھرے ہوئے کے ہوتے ہیں.کہتے ہیں اَلدِّھَاقُ مِنَ الْکُؤُوْسِ: اَلْمُمْتَلِئَۃُ (اقرب) تو کَاْسًا دِھَاقًا کے معنے ہوئے اُنہیں ایسے پیالےملیں گے جو لبالب بھرے ہوں گے.
Page 86
تفسیر.متقیوں کو لبالب بھرے ہوئے پیالے ملنے کا مطلب پہلے اللہ تعالیٰ نے اَعْنَاب کا ذکر کر کے فرمایاتھا جن سے شراب بنتی ہے.اب یہ بتا یا کہ وہ مذکورہ بالا شرابِ معرفت میں اتنے متوالے ہوں گے کہ ان کا نشہ کبھی ختم ہی نہ ہو گا اور ان کی طبیعتوں میں کہیں سیری حاصل نہیں ہو گی.ایک پیالہ ختم ہو گا تو دوسرا پینا شروع کر دیں گے دوسرا پیالہ ختم ہو گا تو تیسر اپیالہ شروع کر دیں گے یعنی ایک قربانی کرلیں گے تو دوسری کے لئے تیار ہو جائیں گے.دوسری قربانی کریں گے تو تیسری کے لئے تیار ہو جائیںگے گویا محبت الٰہی کا پیالہ وہ سیر ہو کر زمین پر رکھیںگے ہی نہیں.ہر وقت اُن کا پیالہ بھرا ہوا رہے گا اور عشق الٰہی کے نشہ میں انہیںقربانی کی ایسی عادت پڑ جائے گی کہ کسی موقعہ پر بھی اُن کی طبیعت میں سیری نہیں ہوگی اور چونکہ اگلے جہان کی لذتیں روحانی ہوں گی گو یہ بھی صحیح ہے کہ ان کی ایک جسمانی شکل بھی ہو گی مگر بہرحال چونکہ اصلی لذت روحانی ہو گی اس لئے جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ان کو ایسے پیالے ملیں گے جو ہمیشہ بھرے رہیں گے اُن میں کبھی کوئی کمی نہیں آئےگی تو ان الفاظ کو جہاں اگلے جہا ن پر چسپاں کیا جاتاہے وہاں اس کے معنے یہ بھی ہوں گے کہ ان کے دل محبت الٰہی سے ہمیشہ لبریز رہیں گے.قربانی ان کے قدم کو پیچھے نہیں ہٹائے گی بلکہ ہر قربانی کے بعد ان کا دل چاہے گا کہ ہم اور قربانی کریں اور اپنے عشق کا مظاہر ہ کریںاور جب وہ دبارہ اپنے عشق کا مظاہر ہ کریں گے تو ان کے دلوں میں خواہش پیدا ہو گی کہ ہم اپنے عشق کا اب تیسرا مظاہر ہ کریں اور اس طرح یہ سلسلہ چلتا چلا جائے گا.لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا وَّ لَا كِذّٰبًاۚ۰۰۳۶ نہ تو وہ اِن (جنتوں) میں لغوباتیں سنیں گے اور نہ (ایک دوسرے کو) جھٹلانے والا کلام.تفسیر.لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا وَّ لَا كِذّٰبًاکے الفاظ بیان کرنے کی حکمت چونکہ اللہ تعالیٰ نے محبت الٰہی کی مشابہت شراب سے دی تھی اور شراب میں بعض نقائص ہوتے ہیںاس لئے اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی ذکر فرما دیا کہ گو وہ شراب کی طرح محبت الٰہی کے نشہ میں سرشار ہوں گے مگر ہمارا اس سے یہ مطلب نہیں کہ شراب کے نقائص بھی ان میں پائے جاتے ہوں گے.شراب کی خرابی یہ ہے کہ اُس میں لغو بہت ہوتا ہے اسی طرح اُس میں تکذیب ہوتی ہے یعنی شرابی لغو اور فضول باتیںبھی کرتے ہیں.اور آپس میں لڑتے جھگڑتے بھی ہیں.مگرفرمایا لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا وَّ لَا كِذّٰبًا وہ نہ اس میں کوئی لغو بات سنیں گے اور نہ تکذیب کی کوئی بات سنیں گے.لغو سے مراد
Page 87
بکواس اوربےہودہ باتیں ہیں.مجھے یاد ہے میں ایک دفعہ اپنے گھر میں ٹہل رہا تھاجب میں ٹہلتے ٹہلتے اس دیوار کے پاس پہنچا جو گلی کی طرف ہے تو مجھے اس وقت ایک آدمی کی آواز سنائی دی جو دوسرے شخص کا نام لے کر کہہ رہا تھا سندرسنگھا پکوڑے کھانے این یعنی سندر سنگھ کیا پکوڑے کھائو گے.تھوڑی دیرکے بعد اُس نے پھر یہی فقرہ کہا.کچھ دیر گزری تو پھر مجھے یہی آواز آئی مگر دوسری طرف سے کوئی جواب ہی نہیں ملتا تھا.میں نے دیوار پر سے جھانکا تو مجھے نظر آیا کہ مسجد اقصیٰ کے پاس جو موڑ ہے جہاں نظارتوں کے دفاتر ہیں وہ ایک شخص ٹیک لگائے شراب کے نشہ کی حالت میں یہ فقرہ دوہراتا چلا جا رہا ہے اور اُس کا مخاطب ساتھی اُس وقت وہاں تک پہنچ چکا تھا جہاں اُم طاہر کا مکان ہے یعنی کہنے والے سے کوئی پچاس گز کے فاصلہ پر.مگر وہ یہی کہتا جا رہا تھاکہ سندر سنگھ پکوڑے کھانے ہیں.اس طرح وہ کتنی ہی دیر وہاں پر بیٹھا یہ فقرہ دُہراتا رہا حالانکہ دُوسرا شخص اُس وقت تک غالباً دوسرے گائوں تک پہنچ چکا ہوگا.جنت کی نعماء کو لغو اور کذاب سے پاک رکھے جانے سے ان کے تین فوائد کی طرف اشارہ غرض شراب میں یہ ایک بہت بڑا نقص ہے کہ انسان لغو باتیں کرنے لگ جاتا ہے.دُوسرا نقص اس میں یہ ہے کہ اس کے پینے والا دوسرے سے لڑنے جھگڑنے اور اُسے گالیاں دینے لگ جاتا ہے.کِذَّابًا کَذَّبَ کا مصدر ہے اور اس کے معنے ایک دوسرے کو جھٹلانے کے ہوتے ہیں.ایک کہتا ہے تُو نے یہ کہا تھا.دوسرا کہتا ہے مَیں نے یہ نہیں کہا تھامیں نے تو وہ بات کہی تھی.اس وجہ سے اُسی شرابی کا ذکر کر کے قرآن کریم فرماتا ہے لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا وَّ لَا كِذّٰبًا جنت کی نعماء خواہ شراب کے پیالوں میں ملیں.خواہ عشق الٰہی کی شراب کے پیالے ان کو پلائے جائیں.اس شراب کی یہ خصوصیت ہے کہ اس میں لغو نہیں ہو گا اورنہ کِذّاب ہو گا.لغو سے انسان کا وقت ضائع ہوتا ہے اِسی لئے شراب پی کر انسان ایسی باتوںکی طرف متوجہ ہو جاتا ہے جو وقت کو ضائع کرنے والی ہوتی ہیں.مثلاًجوا عام طور پرشراب پی کر ہی کھیلا جاتا ہے.لیکن لغو نہ ہونے سے اولؔ وقت ضائع نہیں ہوتا.دومؔ ذہن کام کے سوادوسرے امور کی طرف متوجہ نہیں ہوتا اور توجہ کے قیام سے ترقی جلد جلد ہوتی ہے.جب انسان لغو امور کی طرف توجہ کرتا ہے تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں اپنے وقت کوضائع کر دیتا ہے اور توجہ کا اجتماع پیدا نہیں ہوتا.لیکن جہاں لغو نہ ہو وہاں اجتماعِ توجہ خوب ہوتا ہے اور کام کی چیزوں کی طرف توجہ رہتی ہے.اور چونکہ اس کی عادت میں بات داخل ہو جاتی ہے کہ وہ کام کی طرف توجہ کرے.لغو کاموں میں حصہ نہ لے.اس لئے اس کے اندر غور اور فکر کی قوت بڑھ جاتی ہے اور ہر بات کی طرف توجہ کرنے کی اُسے عادت پیدا ہو جاتی ہے.تیسراؔ فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس کے نتیجہ میں ہر حصہ کام
Page 88
اور ہر حصہ قوم مفید ضرورت میں لگ ر ہا ہوتا ہے جب انسان لغو نہیں کرے گا تو لازماً وہی کام کرے گا جو ضروری ہو گا اور جس کا مفید نتیجہ نکل سکے گا اور جب ساری قوم ایسے ہی کاموں میں حصہ لے گی جن کے مفید نتائج نکل سکتے ہوں تو قومی ترقی جلد جلد ہو گی.پس لغوؔ کی طرف توجہ نہ کرنے کے تین فوائد ہیں.اولؔ اس کے نتیجہ میں وقت ضائع نہیں ہوتا دومؔ ذہنوں میں مقاصدکی طرف توجہ پیداکرنے کی عادت پیدا ہوتی ہے سومؔ اُو پر کی دو باتوں کے نتیجہ میں قوم جلد جلد ترقی کی طرف قدم اُٹھاتی ہے.وَلَا کِذَّابًا: پھر شراب سے لڑائی جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے مگر یہ وہ نشۂ محبت ہے جس میں کذاب نہیں جس میں لڑائی اور جھگڑے کی کوئی صورت نہیں بلکہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی تائید اور تصدیق کرنے والا ہی ہوگا.کِذَّاباور تَکْذِیْب بھی قومی ترقی کی جڑ کو لغو کی طرح کاٹنے والی چیز ہے جو شخص دوسرے کی تکذیب نہیں کرتا لازمی بات ہے کہ وہ حسن ظنّی کرے گا کیونکہ تکذیب نہ کرنے کا لازمی نتیجہ حسن ظنی ہے اور جب وہ حسن ظنی کرے گاتو لازمی بات ہے کہ اس کے نتیجہ میں دلوں کو اطمینان حاصل ہو گا.ساری خرابی بدظنی سے ہی پیدا ہوتی ہے.اگر انسان بد ظنی سے کام لینے لگے تو وہ یہ بھی خیال کر سکتا ہے کہ میری بیوی نے کہیںکھانے میں زہر نہ ملا دیا ہو.لیکن اگر اس طرح انسان خیال کرنے لگے تو یہ دنیا ہی دوزخ بن جائے.اسی طرح اور بیسیوں معاملات ہیں جن میں حسن ظنی سے کام لینا پڑتا ہے اور اگر انسان شکوک وشبہات میں مبتلا رہے تو اس کے معاملات میں بیسیوں خرابیاں پیدا ہو جائیں.لیکن جب لڑائی جھگڑا نہ ہو اور کاموں کی بنیاد حسن ظنی پر ہو تو دلوں کو اطمینان رہتا ہے اور یہ ایک بہت بڑی قومی نعمت ہے جو حسن ظنی سے حاصل ہوتی ہے.پھراس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ قومی تعاون حاصل ہوتاہے جب انسان حسن ظنی سے کام لے گا تونیکی کے کاموں میں وہ دوسروں کی مدد بھی کرے گا اور ان کے تعاون کو بھی قدر کی نگا ہ سے دیکھے گا اور اس طرح ایک دوسرے کے تعاون سے قوم میں ترقی کی روح پیدا ہو گی اگر انسان یہ خیا ل کرے کہ فلاں شخص تو میرا دشمن ہے تو اس کے بعد وہ اس کی مدد کے لئے کھڑا نہیں ہوسکتا لیکن اگر وہ یہ بدظنی نہ کرے اوریہی سمجھے کہ وہ میرا دوست ہے تو مشکلا ت کے وقت وہ اس کی مدد کرنے کے لئے تیار ہو جائے گا.پس حسن ظنی کا دوسرا فائد ہ یہ ہے کہ قومی تعاون کی رُوح اس سے ترقی کرتی ہے.تیسرے حسن ظنی کے نتیجہ میں اقدام عمل کے وقت یہ خوف نہیں ہوتا کہ دوسرے الزام لگا کر میری سکیم کو ناکام بنا دیں گے.بلکہ وہ دوسروں پرحسن ظنی کرتے ہوئے ہر خطرہ کو برداشت کرنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے مثلاً کوئی شخص مصیبت میں مبتلا ہو اور یہ سمجھے کہ اس کے ہمسائے فوراً اس کی مصیبت دور کرنے کے لئے خطرہ میں کود پڑیں گے تو جس دلیری سے وہ مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لئے کھڑا ہو گا اس دلیری
Page 89
سے وہ شخص نہیںکھڑاہو سکتا جو سمجھتا ہے کہ نامعلوم میرے ہمسائے اور دوست میری مدد کریں گے یا نہیں.پس حسن ظنی کی وجہ سے اقدام عمل کے وقت زیادہ دلیری پیدا ہو جاتی ہے اور انسان قوم کی خاطرہربڑی سے بڑی قربانی کے لئے تیار رہتا ہے.غرض یہ تین فوائد ہیں جو حسن ظنی سے حاصل ہوتے ہیں دوسری جگہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَا لَغْوٌ فِیْھَا وَلَا تَاْثِیْمٌ نہ جنت میں لغو ہوگا نہ ایک دوسرے پر گناہ کا الزام لگانا (الطور :۲۴)اس جگہ تَاْثِیْمٌ کی جگہ کِذَّاب کالفظ رکھ دیا ہے یہ بتانے کے لئے کہ کِذَّاب اور تَأثِیْم ایک ہی چیز ہیں.کِذَّاب کے معنے ہوتے ہیں ایک دوسرے کی تکذیب کرنا اور تَأثِیْم کے معنے ہوتے ہیں ایک دوسرے پر الزام لگانا.پس یہ دونوں لفظ ہم معنی ہیں.جَزَآءً مِّنْ رَّبِّكَ عَطَآءً حِسَابًاۙ۰۰۳۷ انہیں تیرے رب کی طرف سے بدلہ دیا جائے گا جو منا سب حال انعام ؎۱ ہوگا.الحساب.العد گننا الکافی.کافی (اقرب) پس عَطَآءً حِسَابًاکے معنے ہوں گے (ا) ایسی عطا جو کافی ہوگی.(۲) ایسی عطا جو حساب میں ہو.تفسیر.حساب کے مطابق جزا ء دیئے جانے کا مطلب یہ تیرے رب کی طرف سے بطور جز اء کےہو گا اور عَطَاءً حِسَابًا ہوگی عَطَاءً کا لفظ جَزَاءً کے لئے مفعول مطلق کے طور پر استعمال ہوا ہے یعنی یہ ایسی جزاء ہو گی جو حساب کے مطابق ہو گی.حساب کے مطابق جزاء ہونے سے بظاہر اس امر پر زور معلوم ہوتا ہے کہ وہاں حساب سے زیادہ جزاء نہیں ہو گی حالانکہ قرآن کریم کی بعض دوسری آیتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ خدا رحیمؔ ہے اور انسانی اعمال سے بہت زیادہ جزاء دیتا ہے.پس بظاہر یہ بات اُن آیات کے خلاف نظر آتی ہے کہ ایک جگہ فرمایا گیا ہے کہ ہم مومنوں کو ان کے کام سے زیادہ جزاء دیں گے اور دوسری جگہ یہ فرما دیا کہ حساب کے مطابق جز اء ہو گی.حساب کے مطابق ملنے سے مراد ضرورت کے مطابق ملنے کے اس کے متعلق یاد رکھنا چاہیے کے حساب کے معنے حساب کے مطابق کے علاوہ اور بھی ہوتے ہیںچنانچہ حساب کے ایک معنے گننے کے بھی ہوتے ہیںاور کافی کے بھی ہوتے ہیں (اقرب) یعنی ایسی چیز جس سے ضرورت پوری ہو جائے پس عَطَاءً حِسَابًا کا یہ مطلب ہواکہ ایسی عطا جس سے انسان کی ہر ضرروت پوری ہو جائے.چنانچہ ابن کثیر لکھتے ہیں کَافِیًا وَافِیًا ؎۱ حِسَابًا صفت ہے عَطَائً کی اور عَطَائً مفعول مطلق ہے جَزَائً کا جس کا عامل محذوف ہے.
Page 90
سَالِمًا کَثِیْرًا کہ حِسَابًا کے معنے یہ ہیں کہ جو کچھ ملے گاوہ کافی ہو گا بلکہ ضرورت سے زیادہ ہو گا اور سالم ہوگا یعنی کسی قسم کانقص اُس میں نہیں ہوگا.کَثِیْرًا اور وہ پھر بہت ہوگا.چنانچہ وہ مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں تَقُوْلُ الْعَرَبُ اَعْطَا نِیْ فَاَحْسَبَنِیْ اَیْ کَافَانِیْ یعنی اہل عرب کہتے ہیں اَعْطَانِیْ فَاَحْسَبَنِیْ اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس شخص نے مجھے اتنا دیا کہ میری سب ضرورتوں کو پورا کر دیا.پھر کہتے ہیں وَمِنْہُ حَسْبِیَ اللّٰہُ اَیِ اللّٰہُ کَافِیَّ اسی سے حَسْبِیَ اللّٰہ نکلاجس کے معنے یہ ہیں کہ اللہ میرے لئے کافی ہے.عَطَآءً حِسَابًا سے مراد پہلے سے وعدہ دی گئی عطاء لیکن حِسَابًا کے اس جگہ ایک اور معنی بھی ہیں اور وہ یہ کہ انہیں ایسی عطا ملے گی جو حساب میں پہلے ہی موجود تھی یعنی مومن جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ کو یہ یہ جزا ملے گی کیونکہ خدا نے مجھے بتا یا ہوا ہے کہ اس کی طرف سے فلاں فلاں نعمتیں ملیں گی.گویا یہاں حِسَابًا کے یہ معنے ہوں گے کہ ایسی عطا جوپہلے ہی حساب میں آئی ہوئی تھی جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اپنی پیشگوئیوں میںذکر کیا ہوا تھا اور جس کے متعلق مومن یہ امید رکھتا تھا چونکہ خدا نے اپنی پیشگوئیوں میں اس کا ذکر کیا ہوا ہے اس لئے ضروری ہے کہ یہ باتیں ایک دن پوری ہوں اور کافر بھی علم رکھتا تھا کہ مسلمانوں کے متعلق یہ یہ باتیں بیان کی گئی ہیں.پس چونکہ اس عطا کے ساتھ ایک پیشگوئی کا بھی تعلق تھا جس پر مومن بھی ایمان رکھتا تھا اور کافر کو بھی اس کاعلم تھا اس لئے عَطَاءً کے ساتھ حِسَابًا کا لفظ بڑھا دیا.میرے نزدیک عَطَائً حِسَابًا سے مراد وہی عطا ہے جو حساب میں آچکی تھی یعنی جس کا ذکر ہو چکا تھا جس کا مومن کو بھی علم تھا اور کافر کو بھی علم تھا یہاں عَطَاء کی تعداد مراد نہیں بلکہ اس سے عَطَاء کے ملنے کا وعدہ مراد ہے.جیسے کہتے ہیں فلاں چیز تو محسوب ہو چکی ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز ہمارے ریکارڈ میں آچکی ہے.اسی طرح عَطَآءً حِسَابًا کا یہ مطلب ہے کہ وہ سرکاری دیوان میں لکھی ہوئی عطاء ہو گی جس کی پہلے سے پیشگوئی موجود تھی اور جس کا دوست کو بھی علم تھا اور دشمن کو بھی علم تھا.رَّبِّ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمٰنِ لَا يَمْلِكُوْنَ (تیرے اس رب کی طرف سے جو) آسمانوںاور زمین اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے ان سب کا رب ہے مِنْهُ خِطَابًاۚ۰۰۳۸ (اور) بے حد کرم کرنے والا ہے.وہ اس کے حضور میں (بلا) اجازت بات کرنے کی طاقت نہیں رکھیں گے.حل لغات.خِطَابًا: خِطَاب خَاطَبَ کا مصدر ہے.کہتے ہیں خَاطَبَہٗ بِالْکَلَامِ مُخَاطَبَۃً
Page 91
وَخِطَابًا.کَالَمَہُ یعنی اس سے آمنے سامنے ہو کر با ت کی (اقرب) پس خِطَاب کے معنے ہوں گے آمنے سامنے ہو کر بات کرنا.تفسیر.پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا جَزَآءً مِّنْ رَّبِّكَ کہ یہ تیرے رب کی طرف سے جزا ہے اور جزاء رحیمیّت کی علامت ہوتی ہے یعنی جزا اُسی کو ملتی ہے جو کام کرتا ہے پس پہلے تو فرمایا تھا کہ جَزَآءً مِّنْ رَّبِّكَ مگر آگے اَلرَّحْمٰن کا لفظ استعمال فرما دیا جو صفت رحمانیت پر زور دینے کے لئے استعمال ہوتا ہے اور بتاتا ہے کہ اُس ذات کی طرف سے تمہیں یہ جزا ملے گی جو رحمن ہے.یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ رحمٰن اس کو کہتے ہیں جو بغیر کام کے بدلہ دے اور جَزَآءً مِّنْ رَّبِّكَ میں یہ بتایا گیا کہ جزاء کام کے بدلہ میں ہو گی کیونکہ جزاء صفتِ رحیمیت کے تابع ہے صفتِ رحمانیت کے تابع نہیں.پس سوال پیدا ہوتا ہے کہ پہلے صفت رحیمیت کے نتیجہ میں جزاء قرار دے کرآگے صفت رحمانیت کا کیوں ذکر کیا گیا ہے.جزاء کا لفظ بیان کرنے کے بعد لفظ رحمٰن بیان کرنے کی دو حکمتیں اس کے متعلق یہ امر بھی سمجھ لینا چاہیے کہ یہاں اَلرَّحْمٰن کا لفظ لانے میں دو حکمتیں ہیں ایک تویہ کہ رحمٰن کالفظ لا کر اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو کچھ دیا ہے صفت رحیمیت کے ماتحت دیا ہے مگر وہ صرف رحیم ہی نہیں بلکہ رحمن بھی ہے.جب صفتِ رحیمیت کے ماتحت اس نے تمہیں یہ یہ کچھ دے دیا تو تم خود ہی سمجھ لو کہ وہ کیا انعام ہو گا جو صفت رحمانیت کے ماتحت تمہیں ملے گا وہ تو لازمًااس سے بہت بڑا انعام ہو گا کیونکہ وہ کسی کام کے بدلہ میں استحقاق کے طور پر نہیں ہو گا بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی صفت رحمانیت کے ماتحت تمہیں اپنے اس انعام سے حصہ دے گا.گویا وہ خدا جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے جس نے اپنی صفت رحیمیت کے ماتحت تمہیں اپنی نعمتوں سے حصہ دیا اُس کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ رحمٰن ہے جب رحیمیت کے ماتحت اس نے تمہیں ایسی عطا دے دی جو تمہاری تمام ضروریات پر حاوی ہے بلکہ تمہاری ضرورتوں سے بھی زائد ہے تو تم اس کی صفت رحمانیت کے ماتحت آنیوالے انعامات کا اندازہ بھی کب کر سکتے ہو.گویا یہ نہ سمجھو کہ یہ ہمارا آخری انعام ہے بلکہ یہ انعام تو صرف صفت ِرحیمیت کے نتیجہ میں تمہیں حاصل ہؤا ہے صفتِ رحمانیت کے ماتحت جو انعام ملے گا وہ تو بہت ہی زیادہ ہو گا.دوسرے رحمٰن کا لفظ لا کر اس طر ف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ گو ہم اس کے لئے جز اء کا لفظ بولتے ہیں مگر درحقیقت بات وہی ہے جو غالب نے اپنے شعر میں کہی کہ
Page 92
جان دی.دی ہوئی اُسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا (دیوان غالب از مرزا اسد اللہ خان غالب ) فرمایا ہمارا یہ احسان ہے کہ ہم اس کے لئے جز اء کا لفظ استعمال کر رہے ہیں ورنہ تم نے جو کچھ کیا وہ تو ہمارے فضلوںکا ایک طبعی نتیجہ تھا اُس میں تمہاری کون سی قابلیت تھی اگر ہم قرآن کریم نازل نہ کرتے.اگر ہم اپنے کلام میں تمہیں اپنی ہدایت کی راہیں نہ بتاتے تو تم کس طرح وہ مقامات حاصل کر سکتے جو آج تمہیں حاصل ہیں.یہ قرآن ہی تھا جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت کے بلند ترین مقام پر پہنچا دیا.یہ قرآن ہی تھا جس نے ابو بکر کو ابو بکر ؓ.عمر کو عمرؓ.عثمان کو عثمانؓ اور علی کو علیؓ بنایا.بے شک ان لوگوں نے بڑی قربانیاں کیں.بے شک ان لوگوں نے دین کی بڑی خدمتیں کیں مگر یہ سب ہماری صفتِ رحمانیت کا نتیجہ تھا.یہ سب قرآن کا نتیجہ تھا.پس گوہم تمہارے لئے جزاء کا لفظ استعمال کر رہے ہیں مگر اس بات کو بھول نہ جاناکہ یہ محض ہماری صفت رحمانیت کا نتیجہ ہے جیسا کہ قرآن کریم میں دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَلرَّحْمٰنُ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ (الرحمٰن:۲،۳) کہ اگر رحمٰن خدا کی طرف سے قرآن نازل نہ ہوتا.اگر اس کی طرف سے تم پر یہ علوم اور معارف کھولے نہ جاتے تو تم کو وہ مقام کبھی حاصل نہ ہو سکتا جس پر آج تم پہنچے ہوئے ہو.رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ کہہ کر اس طرف اشارہ فرمایا ہے کہ جس رب کی طرف سے تم کو یہ جزاء ملے گی وہ آسمان و زمین اور جو کچھ اُن کے درمیان ہے ان سب کا رب ہے.پس وہ جس پر مہربان ہویہ سب کُچھ اُسے بخش سکتا ہے گویا بخشش کی وسعت کے امکان کی طرف توجہ دلائی گئی ہے.لَا یَمْلِکُوْنَ مِنْہُ خِطَابًا.ان کو اختیار نہیں ہے اُس سے خطا ب کرنے کا.یا اُس سے خطاب کرنے کی وہ طاقت نہیں پاتے.دنیا میں بعض کام ایسے ہوتے ہیں جن میں ایک شخص دوسرے پر زور دے کر اُس سے اپنی بات منوالیتا ہے یا اگر بات نہ منوائے تو اس پر زور ضرور ڈالتا ہے مثلاً زیدؔ بکرؔسے بات کرتا ہے.اب خواہ بکر زیدؔ کی بات کو مانے یا نہ مانے زیدؔ اس سے خطاب کر لیتا ہے.مگر اللہ تعالیٰ کی ہستی ایسی ہے کہ اس جہان میں بھی اور اگلے جہان میں بھی وہ لَا یَمْلِکُوْنَ مِنْہُ خِطَابًا کی شان رکھتی ہے یعنی اُس سے خطاب کرنے پر کوئی انسان مقدرت نہیں رکھتا.دنیا میں تو انسان کو خدا تعالیٰ پر جو ایمان ہوتا ہے وہ ہوتا ہی ایمان بالغیب ہے اس لئے اس میں خطاب کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا لیکن آخرت میں بھی یہی کیفیت ہو گی کہ کوئی انسان اس کی اجازت کے بغیر اُس سے گفتگو کرنے کی
Page 93
مقدرت نہیں رکھے گا.یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا خطاب نہیںکہلاتا کیونکہ خطاب کے معنے ہوتے ہیںآمنے سامنے ہو کر بات کرنا اور اس طرح خدا تعالیٰ سے بالمشافہ گفتگو کرنے کی کسی انسان میں طاقت نہیں ہے اگلے جہان میں بھی ایسا ہی ہو گاجس کو اجازت ہو گی بولے گا اور جس کو اجازت نہیں ہو گی نہیں بولے گا.اور درحقیقت لَا یَمْلِکُوْنَ مِنْہُ خِطَابًا سے مراد ہی یہ ہے کہ یہ چیز اختیاری نہیں ہو گی ورنہ یہ مراد نہیں کہ ایسا ہوگا ہی نہیں.لَا یَمْلِکُوْنَ مِنْہُ خِطَابًامیں صفت رحمانیت کی طرف اشارہ لَا یَمْلِکُوْنَ مِنْہُ خِطَابًا میں اللہ تعالیٰ کی صفتِ رحمانیت کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے اس سے پہلے اَلرَّحْمٰن کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا تھا جس میں اس امر کی طرف اشارہ تھا کہ یہ ہمارا احسان ہے کہ ہم نے تم پر اپنا کلام نازل کیا ورنہ کسی انسانی عمل کے نتیجہ میں کلامِ الٰہی نازل نہیں ہوا کرتا.پس رحمٰن کے لفظ میں جو اشارہ تھا کہ ہماری صفتِ رحمانیت کے نتیجہ میں ہی محمد صلے اللہ علیہ وآلہٖ وسلم ا ٓئے ہیںاگر ہم محمدصلے اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کو نہ بھیجتے اور اگر قرآن ہماری طرف سے نازل نہ ہوتا تو تمہیں یہ ترقیات بھی نصیب نہ ہوتیں اور نہ ہماری طرف سے تمہیں کوئی جز اء ملتی.پس یہ جزاء جو تمہیں مل رہی ہے درحقیقت نتیجہ ہے خدائی کلام کا.مگر لَا یَمْلِکُوْنَ مِنْہُ خِطَابًا.کسی انسان میں اُس سے خطاب کرنے کی طاقت نہیں وہ آپ جب فضل نازل کرنا چاہے نازل کر دیتا ہے انسانی مقدرت اور کوشش کا اس میں دخل نہیں ہوتا.گویا رَّبِّ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمٰنِ لَا يَمْلِكُوْنَ مِنْهُ خِطَابًا میں رحمٰن کا لفظ جو بظاہر زائد لایا گیا تھا اس کی وجہ بیان کر دی کہ تمہارے بس اور طاقت کی یہ بات نہیںتھی کہ تم اس قدر ترقی کر جاتے.تم نے جو کچھ ترقی کی ہے کلام الٰہی پر عمل کے نتیجہ میں کی ہے اور کلام الٰہی اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت کا نتیجہ ہوتا ہے زور سے اُسے حاصل نہیں کیا جا سکتا.يَوْمَ يَقُوْمُ الرُّوْحُ وَ الْمَلٰٓىِٕكَةُ صَفًّا١ۙۗؕ لَّا يَتَكَلَّمُوْنَ (یہ اس دن ہو گا ) جس دن کہ روح کامل اور فرشتے صف باندھ کر کھڑے ہوں گے (اور) وہ بات نہ کر سکیں گے اِلَّامَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَ قَالَ صَوَابًا۰۰۳۸ سوائے اس کے جسے رحمان (خدا) نے اجازت دی ہو گی.اور وہ (مناسب موقعہ) ٹھیک ٹھیک بات کہے گا.حل لغات.اَلرُّوْحُ: اَلرُّوْح اَلْ اور رُوْح کا مجموعہ ہے.اَلْ مختلف اغراض کے لئے کسی لفظ پر داخل کیا جاتا ہے.اِن اغراض میں سے ایک یہ غرض بھی ہے کہ یہ بتایا جائے کہ جس لفظ پر اَلْ داخل ہوا ہے وہ فرد اپنے
Page 94
افراد میں سے کامل ہے چنانچہ کہتے ہیں اَنْتَ الرَّجُلُ یعنی مرد کے کمالات کو اگر دیکھا جائے تو اس کی تعریف تجھ پر ہی صادق آتی ہے.باقی مردوں میں کچھ نہ کچھ نقص ہیں.(اقرب) یہاںاَلرُّوْحُ میںبھی اَلْ کمال کے اظہار کے لئے لایا گیا ہے اور مراد یہ ہے کہ ارواح میں سے کامل روح.اَلصَّوَابُ: اَلصَّوَابُ اَللَّائِقُمناسب.اَلْحَقُّ پکی بات.ضِدُّالْخَطَإِ درست بات (اقرب) تفسیر.یَوْمَ یَقُوْمُ ظرف ہو سکتا ہےلَا یَمْلِکُوْنَ کا بھی اور لَا یَتَکَلَّمُوْنَ کا بھی یعنی لَا یَمْلِکُوْنَ یَوْمَ یَقُوْمُ الرُّوْحُ وَالْمَلَآئِکَۃّ صَفًا یا لَایَتَکَلَّمُوْنَ یَوْمَ یَقَوْمُ الرُّوْحُ وَالْمَلٰٓئِکَۃُصَفًا میں نے جو معنے کئے ہیں اس کے لحاظ سے یَوْمَ یَقَوْمُ الرُّوْحُ والی آیت لَایَتَکَلَّمُوْنَ سے زیادہ تعلّق رکھتی ہے گو لَایَمْلِکُوْنَ سے بھی اس کا تعلق ثابت ہے.بہرحال میرے معنوں کے رُو سے اگر اس آیت کو لَا یَتَکَلَّمُوْنَ کے ساتھ لگایا جائے تو زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے.يَقُوْمُ الرُّوْحُ کے فقرہ میں ارواح سے مراد مفسرین کے نزدیک اللہ تعالیٰ فر ماتا ہے يَوْمَ يَقُوْمُ الرُّوْحُ وَ الْمَلٰٓىِٕكَةُ صَفًّا جس دن روح بھی اور ملائکہ بھی صف باندھ کر کھڑے ہوں گے.یہاں روح کے متعلق سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے.ابن عباس ؓ کہتے ہیں کہ اس سے ارواح بنی آدم مراد ہیں.حسن ؔاور قتادہؔ کہتے ہیں کہ اس سے بنو آدم مراد ہیں.شعبی اور سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ اس سے مراد جبریل ہے اور وہ نَزَلَ بِہٖ الرُّوْحُ الْاَمِیْنُ (الشعرآء:۱۹۴) سے استدلال کرتے ہیں گویا مفسّرین کے نزدیک روح سے مراد ارواح بنی آدم بنو آدم یا جبریل ہے بعض نے یہ معنے بھی کئے ہیں گو یہ بالکل لغو ہیں کہ اس سے مراد انسانوں کے سوا کوئی اور جنس ہے مگر یہ بالکل لغو بات ہے جب تک قرآن سے ایسی بات ثابت نہ ہو اُسے پیش کرنا خلاف عقل ہے.لیکن باقی معنے ایسے ہیں جو اس آیت پر چسپاں کئے جا سکتے ہیں.حضرت ابن عباس ؓکے قول سے اتنی بات ضرور معلوم ہوتی ہے کہ وہ اگلے جہاں کی زندگی کو اسی جسم کے ساتھ نہیں سمجھتے تھے بلکہ وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ انسانی جسم فنا ہو جاتے ہیںاور ارواح انسانی کو اگلے جہان میں زندگی دی جاتی ہے اسی لئے انہوں نے معنے یہ کئے ہیں کہ اس سے ارواح بنی آدم مراد ہیں.لیکن حسن اور قتادہ کہتے ہیںکہ اس سے بنو آدم مراد ہیں گویاوہ اس بات کے قائل تھے کہ زندگی اسی مادی جسم کے ساتھ ہو گی.یہ بھی ایک اختلاف ہے جو مسلمانوں میں دیر سے چلا آ رہا ہے کہ یہی جسم دوبارہ زندہ ہو گا یا کوئی اور جسم ہو گا.ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہاں جسم توضرور ہو گا مگر وہ ایک روحانی جسم ہو گایہ موجودہ جسم نہیں ہو گا.یہ جسم مٹی میں مل کر فنا ہو جائے گا البتہ اس کے کسی باریک حصہ کو لے کر جسے درحقیقت روحانی حصہ ہی کہنا چاہیے اللہ تعالیٰ اُسے نشوونما دینا
Page 95
شروع کر دے گااور اُسے انسان کا جسم بنا دے گا.انسان اپنے ذہن میں اس جسم کو اسی جسم کا ایک تسلسل سمجھے گا اور یہی یقین رکھے گا کہ میں وہی آدمی ہوں جو دنیا میں ہوا کرتا تھا مگر وہ جسم اور ہو گا.حضرت ابن عباسؓ کے قول سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ اگلے جہان میں ہر انسان کو رُوحانی جسم ملے گا کیونکہ وہ رُوح سے ارواح بنی آدم مراد لیتے ہیں صرف بنو آدم مراد نہیں لیتے.معلوم ہوتا ہے خود قتادہ کو جو اُن کے شاگرد تھے یہ شبہ پیدا ہوا ہے کہ میرے اُستاد تو ارواح بنی آدم مرادلے رہے ہیں اور اس طرح اُن کے اپنے عقیدے سے وہ اختلاف رکھتے ہیں.چنانچہ قتادہ کہتے ہیں ھَذَا مَاکَانَ یُخْفِیْہٖ ابْنُ عَبَّاسٍ کہ ابن عباس کا مطلب درحقیقت بنو آدم سے ہی تھا مگر انہوں نے اسے لفظوں میں چھپا دیا.حالانکہ اُن کو اخْفا کی کیا ضرورت تھی.معلوم ہوتا ہے ابن عباس کا یہی عقیدہ تھا کہ جو شخص مرجا تا ہے اس کا جسم فنا ہو جاتا ہے زندگی صرف روح کو ہی ملتی ہے.بہرحال یہ سارے معنے وہ ہیں جو اگلے جہان پر ہی چسپاں ہوتے ہیں اس جہان پر چسپاں نہیں ہوتے.جیسا کہ میں بتا چکا ہوں اس سورۃ میں غلبۂ قرآن.غلبۂ اسلام اور قیامت تینوں چیزوں کا ذکر ہے اور تینوں چیزیں مراد لی جا سکتی ہیں لیکن یہ معنے تینوں مقامات پر چسپاں نہیں ہوتے.بے شک قیامت پہ چسپاں ہو جائیں گے مگر غلبۂ قرآن یا غلبۂ اسلام پر چسپاں نہیں ہو سکیں گے.الروح سے مراد آنحضرت کی روح اس لئے اب میں وہ معنے بتاتا ہوں جو اس دنیا پربھی چسپاں ہو جاتے ہیں اور اگلے جہان پر بھی چسپاں ہو جاتے ہیں اور وہ معنے یہ ہیںکہ میں اَلرُّوحُ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحِ کامل مراد لیتا ہوں اور یَوْم سے مراد قیامت کا وہ دن لیتا ہوں جب رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے اور یہ معنے ایسے ہیں جن کی قرآن اور حدیث دونوں سے تصدیق ہوتی ہے.حدیثوں سے صاف پتہ لگتا ہے کہ قیامت کے دن لوگوں پر سخت گھبراہٹ طاری ہو گی اُس وقت آپ فرماتے ہیں کہ میں خدا کے سامنے جا کر لوگوں کی شفاعت کروں گا پس روح سے مراد اس جگہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کی روح کامل ہے.تو آیت يَوْمَ يَقُوْمُ الرُّوْحُ وَ الْمَلٰٓىِٕكَةُ صَفًّا کے معنے ہوں گے جس دن کھڑی ہو گی روحِ کامل اور کھڑے ہوں گے ملائکہ صف باندھ کر.لَا یَتَکَلَّمُوْنَ اس وقت کوئی نہیں بولے گا اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَہُ الرَّحْمٰنُ سوائے اس کے جسے خدا اجازت دے گا اور کہے گا کہ تُو لوگوں کی شفاعت کر سکتا ہے.اَذِنَ لَہُ الرَّحْمٰنُ کے الفاظ بھی بتا رہے ہیں کہ یہاں شفاعت کا ہی ذکر ہو رہا ہے کیونکہ شفاعت ہی ایک ایسی چیز ہے جو اذن سے ہو گی اور وہی لوگ شفاعت کریں گے جنہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی اجازت ملے گی.چنانچہ حدیثوں میں آتا ہے.رسول کریم صلے اللہ علیہ وآلہٖ وسلم فرماتے ہیں جب قیامت کا دن آئے گا فَیَشْفَعُ النَّبِیِّوْنَ وَالْمَلٰئِکَۃُ وَالْمُؤْمِنُوْنَ فَیَقُوْلُ الْجَبَّارُ بَقِیَتْ
Page 96
شَفَاعَتِیْ (بخاری کتاب التوحید باب قول اللہ تعالیٰ وجوہ یومئذ ناضرة الی ربھا ناظرة ) کہ انبیاء بھی شفاعت کریں گے اور ملائکہ بھی اور مومن بھی اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ انبیاء نے بھی شفاعت کر لی.ملائکہ نے بھی شفاعت کر لی مومنوں نے بھی شفاعت کر لی.اب صرف میں باقی رہ گیا ہوں.چنانچہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی اور بہت سے لوگ دوزخ سے نجات پا جائیں گے.لَا یَتَکَلَّمُوْنَ میں آنحضرت ؐ کے قیامت کے دن شفاعت کر نے کی طرف اشارہ یہ اعتراض کرنا کہ اگر یہاں شفاعت کا ذکر ہے تو پھر رسول کریم صلے اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کے سوا اور لوگوں کی شفاعت کا کیوں ذکر نہیں.درست نہ ہو گا.کیونکہ جب بادشاہ کا ذکر کر دیا جائے تو اس کے وزراء اور سکرٹریوں وغیرہ کا ذکر اس میں شامل ہوتا ہے کیونکہ وہ اس کے تابع ہوتے ہیں.جب یہ کہہ دیا گیا ہے کہ رسول کریم صلے اللہ علیہ وآلہٖ وسلم قیامت کے دن لوگوںکی شفاعت فرمائیں گے تو باقی انبیاء اور شہدا ء اور صلحاء وغیرہ کا اسی میں ذکر آگیا کیونکہ جب روح کامل کا ذکر کر دیا گیا تو دوسری ارواح جو اس سے نچلے درجہ کی ہیں اُن کا ذکر اسی میں خود آگیا اسی طرح گزشتہ انبیاء کی روحیں بھی اَلرُّوْحُ میں شامل سمجھی جائیں گی.پس لَا یَتَکَلَّمُوْنَ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَہُ الرَّحْمٰنُ نے صاف بتا دیا کہ یہاںشفاعت کا ہی ذکر ہے اور شفاعت جس روح نے کرنی ہے وہ رسول کریم صلے اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کی ہی رُوح ہے اور اَلرُّوْحُ سے مراد رسول کریم صلے اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کے سوا اور کوئی نہیں.يَوْمَ يَقُوْمُ الرُّوْحُ کا اظہار اس دنیامیں اس دنیا میں بھی ایسا ہی ہوا.محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی روح جب کھڑی ہوئی تو ملائکہ آپ کے ساتھ تھے.اس لحاظ سے اس آیت کو اسلامی جنگوں کے متعلق بھی سمجھا جائے گااور مراد یہ ہو گی کہ جب دشمنوں کے مقابلہ کے لئے رسول کریم صلے اللہ علیہ وآلہٖ وسلم نکلیں گے تو فرشتوں کی فوج صف باندھ کرآپ کے ساتھ ہو گی اور وہ آپ کی مدد کریں گے چنانچہ قرآن کریم میں يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ اٰلٰفٍ مِّنَ الْمَلٰٓىِٕكَةِ مُسَوِّمِيْنَ (آل عمران :۱۲۵) کے الفاظ آتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے بعض جنگوں میں پانچ پانچ ہزار ملائکہ کے لشکر کے ساتھ مسلمانوں کی مدد کی.ان معنوں کو مدنظر رکھتے ہوئے يَوْمَ يَقُوْمُ الرُّوْحُ وَ الْمَلٰٓىِٕكَةُ صَفًّا سے خاص طور پر فتح مکّہ کی طر ف اشارہ سمجھا جائے گا.وہ وقت ایسا تھا کہ جیسے ایک غالب بادشاہ سے مغلوب قوم ڈرتی ہے اسی طرح مشرکین مکہ ڈرتے اور کانپتے ہوئے آپ ؐکے سامنے پیش ہوئے اُن کے اندر یہ طاقت ہی نہیں تھی کہ وہ بول سکیں.سوائے اس کے کہ رحمٰن خدا کے حکم سے رسول کریم صلے اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کی طرف سے انہیں بولنے کی اجازت ملتی.اس میں کیا شک ہے کہ جہاں تک انسانی انصاف کا سوال ہے کفّار مکّہ سخت سزا کے مستحق تھے مگر رحمن خدا نے
Page 97
ان کے لئے بخشش کا فیصلہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو سنا دیا تھا پس جب کفار مکہ نے رسول کریم صلے اللہ علیہ وآلہٖ وسلم سے کہا کہ ہم سے وہی سلوک کرو جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کیا تو انہوں نے اسی سبق کو دُہرایا جو رحمن نے قرآ ن کریم میں ان کو دیا تھا کہ ہم نے محمدؐ کو مثل یوسف بنایا ہے اور جب محمد رسول اللہ صلعم نے معاف فرما یا تب بھی رحمٰن کے حکم ہی کو دُہرایا.لَا يَتَكَلَّمُوْنَ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ میںدربار محمدیؐ کا نقشہ پھر تیسرے معنوں کے لحاظ سے اس میں غلبۂ اسلام کی طرف بھی اشارہ ہے اور مراد یہ ہے کہيَوْمَ يَقُوْمُ الرُّوْحُ جس دن ہمارا رسول محمد صلے اللہ علیہ وآلہٖ وسلم تم پر فتح حاصل کر کے کھڑا ہو گا وَ الْمَلٰٓىِٕكَةُ صَفًّا اور ملائکہ اس کے ساتھ صف باندھے کھڑے ہوںگے.یہاں ملائکہ سے ہم فرشتے مراد نہیں لیں گے بلکہ مراد یہ لیں گے کہ ایسے لوگوں کی جماعت آپ کے ساتھ ہو گی جو ملائکہ صفت ہوں گے.اسلام کی منظم حکومت دنیا میں قائم ہو جائے گی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست دنیا سے خطاب کریں گے لَا یَتَکَلَّمُوْنَ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَہُ الرَّحْمٰنُ اُس وقت وہی بولے گا جسے خدا کی طرف سے بولنے کی اجازت ہو گی یعنی محمد رسول اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کے دربار میں بولنے والے ایسے ہی ہوں گے جن کو خدا نے اجازت دی ہو گی کہ وہ بولیں.وَقَالَ صَوَابًا اور وہ جو بھی مشورہ دیں گے بالکل صحیح ہو گا.گویا محمد صلے اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی جماعت ملے گی جس کی بڑی خوبی یہ ہو گی کہ وہ تب بولے گی جب خدا اُسے حکم دے گا وہ کوئی کام خدا کے حکم کے بغیر نہیں کرے گی.جو کچھ کہے گی خدا کے حکم کے مطابق کہے گی اور جو کچھ کرے گی خدا کے حکم کے مطابق کرے گی.باقی لوگوں کا یہ حال ہے کہ وہ خدا کی اجازت کی طرف نہیں دیکھتے بلکہ اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں.خدا نے نہیں کہا کہ رنڈیوں کا ناچ دیکھو مگر وہ رنڈیوں کا ناچ دیکھتے ہیں.خدا نے نہیں کہا کہ تم بے ہودہ اور گندے گانے سنو مگر وہ اپنی ساری لذّت انہی گندی گانوں میں سمجھتے ہیں.خدا نے نہیں کہا کہ لغو قصّے کہانیوں میں اپنا وقت گزارو.مگروہ اپنا اکثر وقت ایسی ہی گندی کتابوں اور ناولوں کے پڑھنے میں صرف کر دیتے ہیں.گویا وہ جو کچھ کرتے ہیں خدا کے اذن کے بغیر اور اس کے منشاء کے خلاف کرتے ہیں.مگر محمد صلے اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کو اللہ تعالیٰ ایسی جماعت دے گا جس کے افراد اُسی وقت بولیں گے جب خُدا اُن سے کہے گا کہ بولو.اس کے بغیر وہ کوئی بات نہیں کریں گے وَقَالَ صَوَابًا اور پھر وہ سچے مشورے دینے والے ہوں گے جھوٹے مشورے دینے والےاور خوشامدی نہیں ہوں گے گویا ان آیات میں دربار محمدؐی کا نقشہ کھینچا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ وہ اِس اِس طرح ہو گا.يَقُوْمُ الرُّوْحُ سے مراد غلبہ اسلام اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس دن ہمارے رسول کی روح کھڑی ہوئی اور روح
Page 98
کے کھڑے ہونے سے یہ مراد ہے کہ وہ دنیا پر غالب آگئی.گویا قیام سے مراد ظاہری قیام نہیں بلکہ دُنیا پر غالب آنا اور اُسے اپنے زیرِنگیں کر لینا ہے.فرمایا جس دن یہ کامل روح کھڑی ہو جائے گی اور ملائکہ اس کے ساتھ صف باندھے کھڑےہوں گےتو لَا یَتَکَلَّمُوْنَ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَہُ الرَّحْمٰنُ وَقَالَ صَوَابًا وہ لوگ جو اس کے ساتھی ہوں گے اُن کی یہ خصوصیت ہو گی کہ وہ نہیں بولیں گے جب تک خدا اُن کو بولنے کے لئے نہ کہے.وہ اُسی وقت بولیں گے جب خدا کی طرف سے ان کو بولنے کا حکم ہو گا اور اُسی قدر بولیں گے جس قدر بولنے کا خدا انہیں حکم دے گا.وہ لغو اور بےہودہ باتیں محمد صلے اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کی مجلس میں نہیں کریں گے بلکہ ہر بات خدا تعالیٰ کے احکام اور اس کی ہدایت کے مطابق کریں گے قرآن کریم میں بعض اور جگہ بھی اس کے متعلق اشارے پائے جاتے ہیں.مثلاًایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہےلَا تَسْـَٔلُوْا عَنْ اَشْيَآءَ اِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ (المائدۃ:۱۰۲) اس آیت کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے لغو سوالات سے صحابہ کو روک دیا کہ یہ رسول کریم صلے اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کی مجلس کے آداب کے خلاف ہے.اور فرمایا کہ ایسی باتیں نہ پوچھو جن کاپوچھنا تمہارا خدا پسند نہیں کرتا بلکہ ایسی ہی باتیں پوچھو جن کا پوچھنا تمہارا خدا پسند کرتا ہے.یہی بات اس آیت میں بیان کر دی گئی کہ لَا یَتَکَلَّمُوْنَ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَہُ الرَّحْمٰنُ وَقَالَ صَوَابًا صحابہ رسول کریم صلے اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کی مجلس میں وہی باتیں کریں گے جن باتوں کی انہیں خدا کی طرف سے اجازت ہے.اور جب بھی بولیں گے صحیح اور درست مشورہ دیں گے.اُن کے مشوروں میں منافقت نہیں ہو گی.وہ کسی سے ڈر کر بات نہیں کریں گےوہ کسی خود غرضی کے ماتحت کوئی مشورہ پیش نہیں کریں گے بلکہ وہ جو کچھ کہیں گے بالکل درست اور صحیح ہو گا اور جو مشورہ دیں گے وہ سچا مشورہ ہو گا.اُن کے نفس کی کسی خواہش کا اُس میں دخل نہیں ہو گا.ذٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ١ۚ فَمَنْ شَآءَ اتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهٖ مَاٰبًا۰۰۴۰ یہ دن ہو کر رہنے والا ہے.پس (تم میںسے) جو (شخص) چاہے اپنے رب کے پاس (اپنا) ٹھکانہ بنا لے حل لغات.مَاٰبَ مَاٰبَ کے لئے دیکھو حل لغات سورۃ النّباءآیت ۲۳.اَلْحَقُّ:اَلْحَقُّ کے معنے ہیں اَ لْاَمْرُ الْمَقْضِیُّ فیصلہ شدہ بات.اَلْمَوْجُوْدُ الثَّابِتُ ایسی چیز جو موجود اور ثابت ہو.(اقرب) تفسیر.ذٰلِکَ الْیَوْمُ الْحَقُّ یہ دن آکر رہنے والا ہے.حَقّ کے معنے ہوتے ہیں وَاقع.ثَابت.فَمَنْ شَآءَ
Page 99
اتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهٖ مَاٰبًا.پس جو چاہے اپنے رب کو مَاٰب بنا لے.مَاٰب کے معنے ہوتے ہیں وہ چیز جس کی طرف انسان بار بار لوٹ کر جاتا ہے چونکہ اسلام خدا کو مومن کا معشوق قرار دیتا ہے اس لئے فرماتا ہے اگر تم اپنے دعویٰ ٔ عشق میں صادق ہو تو پھر تمہارا کام یہ ہے کہ جب بھی تم دنیا کے کاموں سے فارغ ہو جائو خدا کو مَاٰب بنائو اور اُسی سے اپنی محبت اور عشق کا اظہار کرو.دوسری جگہ اسی مضمون کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے کہ فَاِذَافَرَغْتَ فَانْصَبْ وَاِلٰی رَبِّکَ فَارْغَبْ (الانشراح:۸،۹) کہ جب تم دنیا کے دھندوں سے فارغ ہو جائو تو پھر خدا کی طرف ہی رغبت کرو اور اُسی کو اپنا مَاٰب بنائو.اُسی کی طرف جائو اور بار بار جائو.مثلاً انسان کو ئی کتاب لکھ رہا ہے تو اِدھر فقرہ ختم ہو اور اُدھر اُس کی زبان سے نکلے سُبحان اللہ.یا ایک شخص کھانا کھا رہا ہوتو اِدھر لقمہ چباتا جائے اور اُدھر سُبحان اللہ سُبحان اللہ کہتا جائے گویا اُس کا مَاٰب صرف خدا ہی ہو اور کسی طرف اُس کی حقیقی توجہ نہ ہو.اس آیت میں اللہ تعالیٰ اس طرف بھی اشارہ فرماتا ہے کہ چونکہ وہ دن آنےوالا ہے جس میں اسلام کو چاروں اطراف میں غلبہ حاصل ہو جائے گا اس لئے کئی لوگوں کے دلوں میں یہ خواہش پید اہو گی کہ ہم کو بھی اس عزت میں سے کچھ حصہ مل جائے ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے کہ اگر تمہاری سچے دل سے یہ خواہش ہے کہ تم بھی ان کامیابیوں میں حصہ لو اور تمہیں بھی کوئی مقام حاصل ہو جائے تو ہماری نصیحت ہے کہ تم اپنے رب کو مَاٰب بنا لو.اور لوٹ لوٹ کر خدا کی طرف جائو.تمہیں کام سے ذرابھی فراغت نصیب ہو.تو تمہارا فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو جائو.اُس سے اپنی محبت بڑھائو.اُس کی طرف دوڑدوڑ کر جائو اور اُس کو اپنی جائے پناہ قرار دو.صرف پانچ وقت کی نمازیں اور تیس دن کے روزے انسان کے کام نہیں آتے بلکہ ہر وقت خدا تعالیٰ کی طرف متوجہ رہنا اور انسان کا بار بار اس کی طرف لوٹنا.یہ چیز ہےجو انسان کے کام آیا کرتی ہے.اِنَّاۤ اَنْذَرْنٰكُمْ عَذَابًا قَرِيْبًا١ۖۚ۬ يَّوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا ہم نے تم کو ایک قریب (ز مانہ میں آنےوالے) عذاب سے یقیناً ہوشیار کر دیا ہے.جس دن کہ انسان اُس کو قَدَّمَتْ يَدٰهُ وَ يَقُوْلُ الْكٰفِرُ يٰلَيْتَنِيْ كُنْتُ تُرٰبًاؒ۰۰۴۱ دیکھ لے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہو گااور کافر (اُس دن) کہہ اُٹھے گا اے کاش! (کاش) مَیں مٹی ہوتا.حل لغات.اَنْذَرْنٰکُمْ اَنْذَرْنٰکُمْ اَنْذَرَ سے متکلم مع الغیر کا صیغہ ہے اور اَنْذَرَہُ بِالْاَمْرِ کے معنے
Page 100
ہوتے ہیں اَعْلَمَہٗ وَحَذَّرَہُ مِنْ عَوَاقِبِہِ قَبْلَ حَلُوْلِہٖ کسی خطر ے سے اس کو آگاہ کیا اور خطرے کے آنے سے پیشتر ہی اُس کے بُرے انجاموں سے خبردار کر دیا (اقرب) پس اَنْذَرْنٰكُمْ کے معنے ہوں گے کہ ہم نے عذاب قریب کے آنے سے پیشتر ہی اس سے اور اس کے انجاموں سے خبردار کر دیا ہے.تفسیر.اِنَّاۤ اَنْذَرْنٰكُمْ کے فقرہ میں غلبہ اسلام کی طرف اشارہ فرماتا ہے ہم نے تمہیں عذابِ قریب سے ڈرا دیا ہے.اس سے صاف پتہ لگتا ہے کہ یہاں اسلام اور قرآن کا غلبہ بھی مراد ہے صرف اگلا جہاں مراد نہیں.کیونکہ یہاں ایک بات سے دوسری بات کا نتیجہ نکالا گیا ہے.فرماتا ہے ہم نے عذابِ قریب سے تمہیں ڈرا دیا ہے.جو ثبوت ہو گا اس بات کا کہ عذابِ بعید بھی آنےوالا ہے.اِنَّاۤ اَنْذَرْنٰكُمْ کے فقرہ میں موعود عذاب کے آنے کا وقت يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدٰهُ: یَوْمَ عَذَابًا کا بدل ہے.پس اس جملہ کے یہ معنے ہیں کہ ہماری مراد اس سے وہ عذاب ہے جس دن انسان اپنے کاموں کے نتائج کو دیکھ لے گا.دیکھنے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اتفاقی طور پردیکھ لے گا بلکہ مراد یہ ہے کہ اُس پر اپنی ناکامی واضح ہو جائے گی.وہ دیکھ لے گا کہ اس نے اپنے کئے کا بدلہ پا لیا.مسلمان جیت گئے اور اُن کے دشمن ذلیل اور رُسوا ہو گئے چنانچہ ایسا ہی ہوا.رسول کریم صلے اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کے غالب آنے کے ساتھ کفّار نے بھی اپنا انجام دیکھ لیا اور مومنوں نے بھی اپنے انعامات دیکھ لئے.یہاں تک کہ ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکررضی اللہ عنہ نے اسی کے نتیجہ میں بادشاہت کا مقام حاصل کر لیا ورنہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی حیثیت کیا تھی.مکّہ کے ایک تاجر سے بڑھ کر اُن کی کوئی حیثیت نہ تھا مگر کُجا مکّہ کا ایک تاجر جسے مکّہ کی ریاست بھی حاصل نہیں تھی اور کُجا یہ کہ وہ ساری وسطی دنیا کے بادشاہ بن گئے.جب وہ بادشاہ ہوئے تو ایک شخص اُن کے والد ابو قحافہ کے پاس دوڑا دوڑا گیا.ابو قحافہ اُن کے والد کی کنیت تھی اور وہ اُن دنوں مکّہ میں تھے.چونکہ رسول کریم صلے اللہ علیہ وآلہٖ وسلم فوت ہو چکے تھے اِس لئے تمام مسلمانوں میں سخت گھبراہٹ تھی کہ اب نا معلوم کون مسلمانوں کا بادشاہ بنتا ہے.وہ دوڑا دوڑا وہاں پہنچا اور کہنے لگا ابو بکر بادشاہ ہوگئے ہیں.اُن کے والد نے یہ بات سُنی تو کہنے لگے کون ابو بکر؟ گویا اُن کو یہ خیال بھی نہیں آسکتا تھا کہ یہ بادشاہ بننے والا اُن کا بیٹا ہو سکتا ہے.اُس نے کہا وہی جو تمہارا بیٹا ہے اَور کون.انہوں نے سوال کرنا شروع کیا.کیافلاں قبیلہ نے مان لیا ؟ کیا فلاں قبیلہ نے مان لیا؟ کیا فلاں قبیلہ نے مان لیا؟جب اُس نے سب سوالوں کا جواب اثبات میں دیا تو وہ کہنے لگے کیا بنو ہاشم نے بھی مان لیا ہے؟ وہ کہنے لگا بنو ہاشم نے بھی مان لیا ہے.اِس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے والد کہنے لگے اللہ! اللہ!محمد صلے اللہ علیہ وسلم سچے رسول تھے جن کے اثر کے نیچے ابو قحافہ کے بیٹے کو
Page 101
عرب کے قبائل اور سرداروں نے اپنابادشاہ تسلیم کر لیا.غرض يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدٰهُ سے اسی طرف اشارہ تھا کہ ہر اِک اپنے اپنے کام کے مطابق نتیجہ دیکھ لے گا.چنانچہ لوگوں نے دیکھ لیا کہ رؤسا عرب ذلیل و رسوا ہو گئے اور ابو قحافہ کے بیٹے کی بنو ہاشم اور بنو عبدالمطلب نے بھی اطاعت اختیار کر لی.مسلمانوں کی شوکت کے ایام میں کافر کا حسرت سے یَا لَیْتَنِیْ کُنْتُ تُرَابًا کہنا اگلے جہاں کے لحاظ سے وَ يَقُوْلُ الْكٰفِرُ يٰلَيْتَنِيْ كُنْتُ تُرٰبًا کے یہ معنے ہوں گے کہ کافر عذاب کو دیکھ کر حسرت کے ساتھ کہے گا کہ کاش میں مٹی ہوتا اور اس عذاب کو نہ دیکھتا.اور اس جہان کے لحاظ سے اس کے یہ معنے ہیں کہ کاش میں مٹی ہوتا اور اس ندامت اور شرمندگی کی ذلّت سے بچ جاتا جو مجھے دیکھنی نصیب ہوئی.چنانچہ مسلمانوں کی شوکت کے زمانہ میں کفّار کی یہی حالت ہوئی.مکّہ کے وہ بڑے بڑے رؤسا اور سردار جو نہایت حقارت کے ساتھ رسول کریم صلے اللہ علیہ وآلہٖ وسلم پر ایمان لانے والوں کو مکّہ کی گلیوں میں گھسیٹا کرتے تھے جب دیکھتے ہوں گے کہ وہ معمولی غلام جن کو ہم خاطر میں بھی نہ لاتے تھے جن کی تحقیر ہمارا دن رات کام تھا اور جن کو مٹانے کی ہم نے بڑی کوششیں کی وہ ہم پر غالب آچکے ہیں اور ہم اُن کے سامنے معمولی غلاموں کی طرح کھڑے ہیں تو اُن کے دلوں میں کیا کیا حسرتیں پیدا ہوتی ہوں گی اور کس طرح وہ اپنے دلوں میں بار بار کہتے ہوں گے کہ کاش ہم اس سے پہلے مر کر فنا ہو چکے ہوتے اور اس شرمندگی اور ذلّت کو دیکھنے سے بچ جاتے.آنحضرت ؐ کو مکہ میں قبول نہ کرنے کی وجہ سے سردران مکہ کے دلوں میں حسرت حضرت عمرؓ ایک دفعہ اپنے زمانۂ خلافت میں مکّہ تشریف لائے تو شہر کے بڑے بڑے رؤسا جو مشہور خاندانوں میں سے تھے اُ ن کے ملنے کے لئے آئے.انہیں خیال پیدا ہوا کہ حضرت عمر ؓ ہمارے خاندانوں سے اچھی طرح واقف ہیں اس لئے اب جب کہ وہ خود بادشاہ ہیں ہمارے خاندانوں کا بھی پوری طرح اعزاز کریں گے اور ہم پھر اپنی گم گشتہ عزت کو حاصل کر سکیں گے.چنانچہ وہ آئے اور انہوں نے آپ سے باتیں شروع کر دیں ابھی وہ باتیں ہی کر رہے تھے کہ حضرت عمرؓ کی مجلس میں بلالؓ آگئے.تھوڑی دیر گزری تو حضرت خبابؓ آگئے اور اسی طرح یکے بعد دیگرے اول الایمان غلام آتے چلے گئے.یہ وہ لوگ تھے جو ان رئوسا یا اُن کے آباء کے غلام رہ چکے تھے اور جن پر وہ اپنی طاقت کے زمانہ میں شدید ترین مظالم کیا کرتے تھے حضرت عمرؓ نے ہر غلام کی آمد پر اُس کا استقبال کیا اور رئوساء سے کہا آپ ذرا پیچھے ہو جائیں اور اُن کو آگے بیٹھنے کے لئے جگہ دے دیں حتیٰ کے وہ نوجوان رئوسا جو آپ سے ملنے آئے تھے ہٹتے ہٹتے دروازہ تک جا پہنچے.اُس زمانہ میں کوئی بڑے بڑے ہال تو ہوتے نہیں تھے ایک چھوٹاسا
Page 102
کمرہ ہو گا اور چونکہ وہ سب اس میں سما نہیں سکتے تھے اس لئے اُن کو پیچھے ہٹتے ہٹتے جوتیوں میں بیٹھنا پڑا.جب مکّہ کے وہ رئوسا جوتیوں میں جا پہنچے اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کس طرح ایک کے بعد ایک مسلمان غلام آیا اور اُس کو آگے بٹھانے کے لئے اُن کو پیچھے ہٹنے کا حکم دیا گیا تو اُن کے دل کو سخت چوٹ لگی.خدا تعالیٰ نے بھی اُس وقت کچھ ایسے سامان پیدا کر دئے کہ یکے بعد دیگرے کئی ایسے مسلمان آ گئے جو کسی زمانہ میں کفّارکے غلام رہ چکے تھے.اگر ایک بار ہی وُہ رئوسا پیچھےہٹتے تو اُن کو احساس بھی نہ ہوتا مگر چونکہ بار بار اُن کو پیچھے ہٹنا پڑا اس لئے وہ اس بات کو برداشت نہ کر سکے اور اُٹھ کر باہر چلے گئے.باہر نکل کر وہ ایک دوسرے سے شکایت کرنے لگے کہ دیکھو آ ج ہماری کیسی ذلّت اور رسوائی ہوئی ہے.ایک ایک غلام کے آنے پرہم کو پیچھے ہٹایا گیا.یَہاں تک کہ ہم جوتیوں میں جا پہنچے.اس پر اُن میں سے ایک نوجوان بولا اس میں کس کا قصور ہے عمرؓ کا ہے یا ہمارے باپ دادا کا؟اگر تم سوچو تو معلوم ہوگا کہ اس میں عمر ؓکا کوئی قصور نہیں.یہ ہمارے باپ دادا کا ہی قصور تھا جس کی آج ہمیں سز ا ملی.کیونکہ خدا نے جب اپنا رسول مبعوث فرمایا تو ہمارے باپ دادا نے مخالفت کی مگر ان غلاموں نے اُس کو قبول کیا اور ہر قسم کی تکالیف کو خوشی سے برداشت کیا اس لئے آج اگر ہمیں مجلس میں ذلیل ہونا پڑا ہےتو اس میں عمرؓ کا کوئی قصور نہیں ہمارا اپنا قصور ہے.اس کی یہ بات سُن کر دوسرے کہنے لگے ہم نے یہ تو مان لیا کہ یہ ہمارے باپ دادا کے قصور کا نتیجہ ہے مگر کیا اس ذلّت کے داغ کو دُور کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں؟ اس پر سب نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہماری سمجھ میں تو کوئی بات نہیں آتی چلو حضرت عمرؓ سے ہی پوچھیں کہ اس کاکیا علاج ہے؟ چنانچہ وہ حضرت عمرؓ کے پاس آئے اور کہنے لگے آج جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہے اُس کو آپ بھی خوب جانتے ہیںاور ہم بھی خوب جانتے ہیں.حضرت عمرؓ فرمانے لگے معاف کرنا میں مجبور تھا کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں معزز تھے.اس لئے میرا بھی فرض تھا کہ اُن کی عزت کرتا.انہوں نے کہا کہ ہم جانتے ہیں یہ ہمارے ہی قصور کا نتیجہ ہے لیکن آیااس عار کو مٹانے کا کوئی بھی ذریعہ ہے؟ ہم لوگ تو اس کا اندازاہ بھی نہیں لگا سکتے کہ اُنہیں مکّہ میں کس قدر رسوخ حاصل تھا لیکن حضرت عمرؓ اُن کے خاندانی حالات کو خُوب جانتے تھے.آپ مکہ میں پیدا ہوئے اور مکہ میں ہی بڑے ہوئے اس لئے آپ جانتے تھے کہ ان نوجوانوں کے باپ دادا کس قدر عزت رکھتے تھے.آپ جانتے تھے کہ کوئی شخص ان کے سامنے آنکھ اٹھانے کی بھی جرأت نہیں کر سکتا تھا.اور آپ جانتے تھے کہ اُنہیں کس قدر رُعب اور دبدبہ حاصل تھا.جب انہوں نے یہ بات کہی تو حضرت عمرؓ کے سامنے ایک ایک کر کے یہ تمام وقعات آگئے اور آپ پر رقّت طاری ہو گئی.اُس وقت آپ غلبۂ رقّت کی وجہ سے بول بھی نہ سکے صرف آپ نے ہاتھ اُٹھایا اور شمال کی طرف انگلی سے
Page 103
آنحضرت ؐ کو مکہ میں قبول نہ کرنے کی وجہ سے سردران مکہ کے دلوں میں حسرت حضرت عمرؓ ایک دفعہ اپنے زمانۂ خلافت میں مکّہ تشریف لائے تو شہر کے بڑے بڑے رؤسا جو مشہور خاندانوں میں سے تھے اُ ن کے ملنے کے لئے آئے.انہیں خیال پیدا ہوا کہ حضرت عمر ؓ ہمارے خاندانوں سے اچھی طرح واقف ہیں اس لئے اب جب کہ وہ خود بادشاہ ہیں ہمارے خاندانوں کا بھی پوری طرح اعزاز کریں گے اور ہم پھر اپنی گم گشتہ عزت کو حاصل کر سکیں گے.چنانچہ وہ آئے اور انہوں نے آپ سے باتیں شروع کر دیں ابھی وہ باتیں ہی کر رہے تھے کہ حضرت عمرؓ کی مجلس میں بلالؓ آگئے.تھوڑی دیر گزری تو حضرت خبابؓ آگئے اور اسی طرح یکے بعد دیگرے اول الایمان غلام آتے چلے گئے.یہ وہ لوگ تھے جو ان رئوسا یا اُن کے آباء کے غلام رہ چکے تھے اور جن پر وہ اپنی طاقت کے زمانہ میں شدید ترین مظالم کیا کرتے تھے حضرت عمرؓ نے ہر غلام کی آمد پر اُس کا استقبال کیا اور رئوساء سے کہا آپ ذرا پیچھے ہو جائیں اور اُن کو آگے بیٹھنے کے لئے جگہ دے دیں حتیٰ کے وہ نوجوان رئوسا جو آپ سے ملنے آئے تھے ہٹتے ہٹتے دروازہ تک جا پہنچے.اُس زمانہ میں کوئی بڑے بڑے ہال تو ہوتے نہیں تھے ایک چھوٹاسا کمرہ ہو گا اور چونکہ وہ سب اس میں سما نہیں سکتے تھے اس لئے اُن کو پیچھے ہٹتے ہٹتے جوتیوں میں بیٹھنا پڑا.جب مکّہ کے وہ رئوسا جوتیوں میں جا پہنچے اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کس طرح ایک کے بعد ایک مسلمان غلام آیا اور اُس کو آگے بٹھانے کے لئے اُن کو پیچھے ہٹنے کا حکم دیا گیا تو اُن کے دل کو سخت چوٹ لگی.خدا تعالیٰ نے بھی اُس وقت کچھ ایسے سامان پیدا کر دئے کہ یکے بعد دیگرے کئی ایسے مسلمان آ گئے جو کسی زمانہ میں کفّارکے غلام رہ چکے تھے.اگر ایک بار ہی وُہ رئوسا پیچھےہٹتے تو اُن کو احساس بھی نہ ہوتا مگر چونکہ بار بار اُن کو پیچھے ہٹنا پڑا اس لئے وہ اس بات کو برداشت نہ کر سکے اور اُٹھ کر باہر چلے گئے.باہر نکل کر وہ ایک دوسرے سے شکایت کرنے لگے کہ دیکھو آ ج ہماری کیسی ذلّت اور رسوائی ہوئی ہے.ایک ایک غلام کے آنے پرہم کو پیچھے ہٹایا گیا.یَہاں تک کہ ہم جوتیوں میں جا پہنچے.اس پر اُن میں سے ایک نوجوان بولا اس میں کس کا قصور ہے عمرؓ کا ہے یا ہمارے باپ دادا کا؟اگر تم سوچو تو معلوم ہوگا کہ اس میں عمر ؓکا کوئی قصور نہیں.یہ ہمارے باپ دادا کا ہی قصور تھا جس کی آج ہمیں سز ا ملی.کیونکہ خدا نے جب اپنا رسول مبعوث فرمایا تو ہمارے باپ دادا نے مخالفت کی مگر ان غلاموں نے اُس کو قبول کیا اور ہر قسم کی تکالیف کو خوشی سے برداشت کیا اس لئے آج اگر ہمیں مجلس میں ذلیل ہونا پڑا ہےتو اس میں عمرؓ کا کوئی قصور نہیں ہمارا اپنا قصور ہے.اس کی یہ بات سُن کر دوسرے کہنے لگے ہم نے یہ تو مان لیا کہ یہ ہمارے باپ دادا کے قصور کا نتیجہ ہے مگر کیا اس ذلّت کے داغ کو دُور کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں؟ اس پر سب نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہماری سمجھ میں تو کوئی بات نہیں آتی چلو حضرت عمرؓ سے ہی پوچھیں کہ اس کاکیا علاج ہے؟ چنانچہ وہ حضرت عمرؓ کے پاس آئے اور کہنے لگے آج جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہے اُس کو آپ بھی خوب جانتے ہیںاور ہم بھی خوب جانتے ہیں.حضرت عمرؓ فرمانے لگے معاف کرنا میں مجبور تھا کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں معزز تھے.اس لئے میرا بھی فرض تھا کہ اُن کی عزت کرتا.انہوں نے کہا کہ ہم جانتے ہیں یہ ہمارے ہی قصور کا نتیجہ ہے لیکن آیااس عار کو مٹانے کا کوئی بھی ذریعہ ہے؟ ہم لوگ تو اس کا اندازاہ بھی نہیں لگا سکتے کہ اُنہیں مکّہ میں کس قدر رسوخ حاصل تھا لیکن حضرت عمرؓ اُن کے خاندانی حالات کو خُوب جانتے تھے.آپ مکہ میں پیدا ہوئے اور مکہ میں ہی بڑے ہوئے اس لئے آپ جانتے تھے کہ ان نوجوانوں کے باپ دادا کس قدر عزت رکھتے تھے.آپ جانتے تھے کہ کوئی شخص ان کے سامنے آنکھ اٹھانے کی بھی جرأت نہیں کر سکتا تھا.اور آپ جانتے تھے کہ اُنہیں کس قدر رُعب اور دبدبہ حاصل تھا.جب انہوں نے یہ بات کہی تو حضرت عمرؓ کے سامنے ایک ایک کر کے یہ تمام وقعات آگئے اور آپ پر رقّت طاری ہو گئی.اُس وقت آپ غلبۂ رقّت کی وجہ سے بول بھی نہ سکے صرف آپ نے ہاتھ اُٹھایا اور شمال کی طرف انگلی سے اشارہ کیا جس کا مطلب یہ تھا کہ شمال میں یعنی شام میں بعض اسلامی جنگیں ہو رہی ہیں اگر تم ان جنگوں میں شامل ہو جائو تو ممکن ہے اس کا کفّارہ ہو جائے چنانچہ وہ وہاں سے اٹھے اور جلد ہی ان جنگوں میں شامل ہونے کے لئے چل پڑے(مناقب امیر المومنین عمر بن الخطاب الباب الثامن و الثلا ثون ذکر عدلہ فی رعیتہ).تاریخ بتاتی ہے کہ اُن میں سے ایک شخص بھی زندہ واپس نہیں آیا سب اسی جگہ شہید ہو گئے اور اس طرح انہوں نے اپنے خاندانوں کے نام پر سے داغِ ذلّت کو مٹا دیا.پیشگوئیوں کے مطابق اسلامی غلبہ یہ لوگ تو مخلص تھے رسول کریم صلے اللہ علیہ وآلہٖ وسلم پر ایمان لا چکے تھے جب اُن کا یہ حال تھا تو سمجھ لو کہ کفّار کا کیا حال ہو تا ہو گا.وہ کس طرح ان حالات کو دیکھ دیکھ کر کُڑھتے ہوں گے اور کہتے ہوں گے ہائے ہم مٹ جاتے.ہم مر کر فنا ہو چکے ہوتے مگر یہ دن ہمیں دیکھنا نصیب نہ ہوتا.جب وہی لوگ جن کو وہ گلیوں میں گھسیٹا کرتے تھے جن کے سینوں پر وہ بڑے بڑے گرم پتھّر رکھ کر انہیں اسلام سے پھرانے کی کوشش کرتے تھے.جن کو مارتے اور گالیاں دیتے اور ہر قسم کے دُکھ پہنچایا کرتے تھے فتح مکہ کے دن گھوڑے دوڑاتے ہوئے آئے ہوں گے اور یہ لوگ اپنے گھروں میں چھپ کر بیٹھ رہے ہوں گے کہ کہیں ان لوگوں کی ہم پر نظر نہ پڑ جائے.تو کس طرح اُن کو اپنی عزتیں خاک میں ملتی ہوئی نظر آتی ہوں گی.کس طرح بار بار اُن کی زبان سے یہ نکلتا ہو گا کہ کاش ہم اس سے پہلے ہی مر کر فنا ہو چکے ہوتے اور اپنی ذلّت کا یہ دن نہ دیکھتے.غرض ابتدائی ایام اسلام میں ہی اللہ تعالیٰ نے وہ سارا نقشہ کھینچ کر رکھ دیا جو آئندہ زمانہ میں اسلام اور مسلمانوں کا ہونے والا تھا.ابھی وہ بہت سے لوگ زندہ تھے.جنہوں نے اس نقشہ کو ایک مجنون کی بڑ سے زیادہ وقعت نہ دی تھی کہ خدا کی بات پوری ہو گئی اور ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے اس نقشہ کے مطابق پیدا ہوتے ہوئے حالات دیکھ لئے.خ خ خ خ
Page 104
سُوْرۃُ النَّازِعَات مَکِیَّةٌ سورۃ نازعات.یہ سورۃ مکّی ہے.وَ ھِیَ سِتٌّ وَّ اَرْبَعُوْنَ اٰیَةً دُوْنَ الْبَسْمَلَةِ وَ فِیْہَا رُکُوْعَانِ اور اس کی بسم اللہ کے علاوہ چھیالیس آیتیں اور دو رکوع ہیں.۱ سورۃ نازعات مکی ہے ۱؎ حضرت عبداللہ بن عباس ؓ اور حضرت عبداللہ بن زبیرؓ کا قول ہے کہ یہ مکی سورۃہے.اور اس کے متعلق کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا.سب مفسّرین کا اس سورۃ کے مکّی ہونے پر اتفاق ہے(فتح البیان سورۃ النازعۃ ابتدائیۃ).سورۃ نازعات کا سورۃ نباء سے تعلق میرے نزدیک اس سورۃ کا پہلی سورۃ سے یہ جوڑ ہے کہ پہلی سورۃ میں بیان کیا گیا تھا کہ مسلمان جو آج تمہیں حقیر نظر آتے ہیں جن کی تعداد دیکھ کر تم ہنستے ہو اور جن کے متعلق تم یہ خیال کرتے ہو کہ انہوں نے دنیا میں کیا تغیّر پیدا کرنا ہے یہ ایک دن تم پر غالب آجائیں گے اور تم ان کے مقابلہ میں بالکل ذلیل ہو جائو گے.چنانچہ سورۃ نبأ میں جو اس وقت نازل ہوئی جب سارے مکّہ میں مسلمانوں کی کل تعداد زیادہ سے زیادہ چالیس تھی بڑے زور سے یہ پیشگوئی کی گئی تھی کہ وہ دن آنےوالا ہےجب مسلمان غالب آجائیں گے اور مشرکین کو حکم دیدیا جائے گا کہ وہ مکّہ سے نکل جائیں.سورۃ نازعات کے مضمون کا خلاصہ جب انبیاء کی طرف سے پیشگوئیاں کی جاتی ہیں تو دنیا میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں.ایک تو وہ ہوتے ہیں جو ہر چیز کو روحانی نظر سے دیکھتے ہیں جب انہیں کہا جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے ایسے کہا ہے تو وہ صرف اس امر کی تحقیق کرتے ہیں کہ آیا خدا تعالیٰ نے ایسا کہا ہے یا نہیں کہا.جب انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ فلاں بات خدا تعالیٰ نے ہی کہی ہے تو ان کو اطمینان حاصل ہو جاتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ جب خدا تعالیٰ نے ایسا کہا ہے تو لازمًا ایک نہ ایک دن ویسا ہی ہوبھی جائےگا اس میں شک کرنے کی کوئی وجہ نہیں.لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی تسلّی محض اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ خدا تعالیٰ ایسا کہتا ہے بلکہ وہ اس کے شواہد اور آثاربھی دیکھنا چاہتے ہیں.گویا ایک خبر کے متعلق باوجود یہ سُن لینے کے کہ وہ خدا تعالیٰ نے دی ہے کسی انسان نے وہ خبرنہیں دی پھر بھی اُن کا دل تسلی نہیں پاتا.بلکہ وہ مادی دُنیا میں اس کی صداقت کے کچھ آثار بھی دیکھنا چاہتے ہیں.وہ کہتے ہیں خدا تعالیٰ بھی جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اسباب اور ذرائع سے کام لیتا ہے.بغیر اسباب اور ذرائع کے کوئی کام نہیں
Page 105
ہوتا.لیکن ہمیں اس دنیا میں وہ سامان نظر نہیں آتے.وہ ذرائع اور وہ اسباب دکھائی نہیں دیتے جن سے یہ کام ہو گا.ان کی فطرتیں تب تسلی پاتی ہیں جب اُن پیشگوئیوں کی صداقت کے متعلق اس مادی دنیا میں آثار ظاہر ہونے شروع ہوجاتے ہیں اگر اس قسم کے آثار ظاہرہونا شروع ہو جائیں تب وہ سمجھنے لگتے ہیں کہ یہی اسباب اور ذرائع ایک دن اس کام کے پورا کرنے کا ذریعہ بن جائیں گے.پس چونکہ دنیا میں بعض طبائع اس قسم کی ہوتی ہیں جن کا اطمینا ن اُس وقت تک نہیں ہوتا جب تک وُہ پیشگوئی کی صداقت کے آثار دیکھنا شروع نہ کر دیں اس لئے جب یہ پیشگوئی کی گئی کہ مسلمان ایک دن غالب آئیں گے اور نہ صرف غالب آئیں گے بلکہ ان کا غلبہ اس قدر بڑھ جائے گاکہ وہ مشرکین کو مکّہ میںسے نکال دیں گے تو ایسے لوگ ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھتے تھے اور کہتے تھے یہ تیس چالیس آدمی ہیں.دشمن ان کو مارتا ہے.پیٹتا ہے.دکھ دیتا ہے.گرم گرم پتھروں پر لٹاتا ہے.مکّہ کی گلیوں میں ان کی ٹانگوں میں رسیاں باندھ کر گھسیٹا جاتا ہے اور ان کی طرف سے کہا یہ جارہا ہے کہ ہم ایک دن ساری دنیا پر غالب آجائیں گے اور مشرکین کو اس سرزمین سے نکال دیں گے آخریہ ہو گا کس طرح؟ ہمیں تو اس مادی دنیا میں اس غلبہ کے ظہور کے کوئی آثار نظر نہیں آتے.پس وہ سوال کرتے تھے کہ یہ غلبہ کیونکر ہو گا؟ سورۃ نازعات میں ان کے اسی سوال کا جواب دیا گیا ہے اور متقیوں کاوہ مَفَاز جس کا سورہ نباء میں ذکر کیا گیا تھا اُس کی تفصیل بتا ئی گئی ہے کہ مومن کس طرح اس دنیا میں ترقی کرنا شروع کریں گے.کس طرح انہیں غلبہ حاصل ہو گا اور کون سے وہ آثار رونما ہوں گے جن سے تم بھی یہ اندازہ لگا سکو گے کہ یہ قوم ایک دن غالب آ جائے گی.اگلے جہان میں مسلمان کو جو کچھ حاصل ہو گا وہ تو ہو گا ہی.سورۃ نازعات میں مسلمانوں کی ترقی کے ذرائع کی طرف اشارہ اس جگہ اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ ہم اسی دنیا میں مسلمانوں کی ترقی کے سامان کریں گے اور مسلمانوں کی یہ ترقی اس بات کا ثبوت ہو گی کہ اگلے جہان کے متعلق اللہ تعالیٰ کے جو وعدے ہیں وہ بھی ایک دن پور ے ہو کر رہیں گے چنانچہ اس سورۃ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اس دَورِ ترقی کی تفصیلات بیان فرمائی ہیں اور پھر جنگوں کی بھی خبر دی ہے گویا بتایا کہ تم جو پوچھتے ہو کہ مسلمانوںکو کس طرح ترقی حاصل ہو گی اس کا جواب یہ ہے کہ جنگیں ہوں گی اور یہ لوگ تم پر غلبہ و اقتدار حاصل کریں گے.گویا بتایا کہ مسلمان اپنی اندرونی اصلاح کے بعد اُسی ہتھیار کی طرف توجہ کریں گے جو آج اُن کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے.اب تو تم ان پر تلوار سے حملہ کر رہے ہو.انہیں دُکھوں پر دُکھ اور تکلیفوں پر تکلیف دیتے چلے جاتے ہو اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم کے ماتحت صبر سے کام لے رہے ہیں تمہارے خلاف اپنا ہاتھ نہیں اٹھاتے مگر ایک دن آئے گا جبکہ یہ دیکھتے ہوئے کہ تم مسلمانوں پر حملہ کرنے سے باز نہیں آ رہے تلوار کا تلوار سے مقابلہ کرنے کا
Page 106
حکم دیا جائے گا اور تمہیں ان مظالم کا مزہ چکھایا جائے گا.جیسے سویا ہوا آدمی بیدار ہو جاتا ہے اسی طرح مسلمانوں کی اندرونی اصلاح اور اُن کی روحانی تربیت کے بعد ایک دن ہم اُن کو بیدار کر دیں گے اور اُنہیں اجازت دے دیں گے کہ اب کھڑے ہو جائو اور تلوار کا تلوار سے مقابلہ کرو.اس کی ایسی ہی مثال ہے جیسے سوئے شیر کے جسم پر ایک چُوہا بھی دوڑ سکتا ہے.مگرجب وہ جاگتا ہے تو ایک مسلّح انسان کے لئے بھی اس کا مقابلہ کرنا مشکل ہوتا ہے.اللہ تعالیٰ بھی اس سورۃ میں یہی مضمون بیان فرماتا ہے کہ پہلے وہ مسلمانوں کو سُلائے رکھے گا.کفّار اُن پر ظلم پر ظلم کرتے چلے جائیں گے اور وہ اُن کے مقابلہ میں زبان تک نہیں ہلائیں گے یہاں تک کہ وہ خیال کرنے لگ جائیں گے کہ مسلمان کیا ہیں مٹی کی مُورتیں ہیں انہیں جس طرح چاہو تکلیف دے لو مگر ایک دن ہم اپنے اس سوئے ہوئے شیر کو جگا دیں گے اور جب سویا ہوا شیر اُٹھتا ہے تو اس کا جسم کانپتا ہے اورپھریری لے کر کھڑا ہو جاتا ہے اُس وقت اس شیر کا مقابلہ کرنا کوئی آسان بات نہیںہوتا.پس اللہ تعالیٰ اس سورۃ میں یہ ـذکر فرماتا ہے کہ ایک دن ایسا ہو گا جب ہمارا یہ شیر ہمارے حکم کے مطابق اُٹھے گا اُس وقت لڑائیوں کا ایک لمبا سلسلہ شروع ہو جائے گا.ایک کے بعد دوسری.دوسری کے بعد تیسری اور تیسری کے بعد چوتھی تبدیلی رُونما ہو گی اور اس طرح مسلمانوں کی ترقی کے لئے مادی تدابیر بھی اختیار کی جائیں گی.گو یہ بھی ایک آئندہ کی ہی خبر ہے مگر جب کسی چیز کی مادی شکل بتا دی جائے تو انسان کو کچھ تسلی ہو جاتی ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اگر ایسا ہو گیا تو بات پوری ہو جائے گی.پہلے تومنکر خیال کرتا تھا کہ شایدقرآن کریم میں سورۂ نبأ میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ فرشتے اُتریں گے اور لوگوں کی گردنیں مروڑ کر انہیں اسلام میں داخل کر دیں گے مگر جب مادی شکل بتا دی گئی تو انسانی نفس جو مادیات کی طرف زیادہ راغب ہوتا ہے اس کے لئے تسلّی پانے کے زیادہ قریبی دلائل پیدا ہو گئے اور اُس کے اطمینان کی مزید صورت پیدا ہو گئی.بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۰۰۱ (میں) اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا (اور) بار بار رحم کرنے والا ہے (پڑھتا ہوں) وَ النّٰزِعٰتِ غَرْقًاۙ۰۰۲ (مجھے ) قسم ہے ان( ہستیوں) کی جو کھینچتی ہیں پوری طرح.حل لغات.نَازِعَات نَازِعَات نَازِعَۃٌ سے جمع کا صیغہ ہے جو نَزَعَ سے اسم فاعل مونث کا صیغہ
Page 107
ہے.نَزَعَ کے کئی مصدر آتے ہیں اس لئے جب نَزَعَ کا مصدر نَزْعًا ہو تو اُس وقت نَزَعَ الشَّیْئَ عَنْ مَکَانِہٖ کے معنے ہوتے ہیں قَلَعَہٗ کسی چیز کو جڑ سے اکھیڑدیا.اور جب نَزَعَ الْاَمِیْرُ الْعَامِلَ کہیں تو اس کے معنے ہوتے ہیں عَزَلَہٗ.امیر نے عامل کو معزول کر دیا.نیز کہتے ہیں نَزَعَ بِالسَّھْمِ اور مراد یہ ہوتی ہے کہ رَمٰی بِہٖ اُس نے تیر پھینکا.اسی طرح کہتے ہیں نَزَعَ فِیْ الْقَوْسِ اَیْ مَدَّھَا اَیْ جَزَبَ وَتْرَھَا یعنی اُس نے کمان کا چلّہ خُوب زور سے کھینچا.اور نَزَعَ عَنِ الْقَوْسِ کے معنے ہوتے ہیں رَمٰی عَنْھَا کمان سے تیر کو پھینکا یعنی تیر اندازی کی.اور نَزَعَ الدَّلْوَ کے معنے ہوتے ہیں جَذَبَھَا وَاسْتَقٰی بِھَا کنوئیں سے ڈول کے ذریعہ پانی کھینچا اور لوگوں کو پلایا اور جب نَزَعَ کا لفظ مریض کے لئے استعمال کریں اور نَزَعَ الْمَرِیْضُ کہیں تو اس کے معنے ہوتے ہیں اَشْرَفَ عَلَی الْمَوْتِ.مریض موت کے قریب پہنچ گیا.چنانچہ اُردو میں بھی کہتے ہیں فلاں شخص کا تو اب نَزْع کا وقت ہے.اور جب نَزَعَ کا مصدر نُزُوْعًا ہوتو نَزَعَ عَنْ کَذَا کے معنے ہوتے ہیں کَفَّ وَانْتَھٰی عَنْہُ وہ کوئی کام کرنے سے رُک گیا اور باز آگیا.اِسی مصدر میں جب کہیں گے نَزَعَ الْوَلَدُ اَبَاہُ یا نَزَعَ الْوَلَدُ اِلٰی اُمِّہٖ تو اس کے معنے ہوتے ہیں اَشْبَہٗ بیٹا اپنے باپ یا اپنی ماں کے مشابہ ہو گیا.اور جب نَزَعَ کا نَزَاعَۃً وَنِزَاعًا وَنُزُوْعًا مصدر ہو تو نَزَعَ اِلَی الشَّیءِ کے معنے ہوں گے اِشْتَھَاہُ اُس نے فلاں چیز کی خواہش کی اور جب کہیں نَزَعَ اَلٰی اَھْلہٖ تو اس کے معنے ہوتے ہیں اِشْتَاقَ اس کے دل میں اپنے رشتہ داروں سے ملنے کا شوق پیدا ہوا.یا انگریزی محاورہ کے مطابق کہیں گے فلاں شخص ہوم سِک HOME SICK ہو گیا.اسی مصدر کے ماتحت جب نَزَعَ بِفُلَانٍ اِلٰی کَذَا کہیں تو اس کے معنے ہوتے ہیں دَعَاہُ اِلَیْہِ اُس نے کسی آدمی کو کسی کام کی دعوت دی.(اقرب) نَازِعَات کےبعد غَرْقًا کا لفظ آتا ہے اس کے متعلق بھی یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ اُردو میں غرق کالفظ جو ڈوبنے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں اُس کا مصدر غَرْقًا نہیں بلکہ غَرَقًا استعمال ہوتا ہے کہتے ہیںغَرقَ غَرَقًا مگر یہاں غَرْقًا اَغْرَقَ ثلاثی مزید کا مصدر استعمال ہوا ہے.گویا غَرْقًا بمعنے اِغْرَاقًا استعمال ہوا ہے اس کی ایسی ہی مثال ہے جیسے پہلے پارہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاِنَّ مِنْھَا لَمَا یَھْبِطُ مِنْ خَشْیَۃِ اللّٰہِ (البقرۃ:۷۵) کہ پتھروں میں سے بعض ایسے ہیں جو خشیۃ اللہ سے گر جاتےہیں.یہاں سب تسلیم کرتے ہیں کہ مِنْ خَشْیَۃِ اللّٰہِ کے الفاظ مِنْ اِخْشَائِ اللّٰہِ کے معنوں میں استعمال ہوئے ہیں.یعنی ڈر کی وجہ سے نہیں بلکہ ڈرانے کی وجہ سے.اسی طرح یہاں غَرْقًا قائمقام اِغْرَاقٌ کا ہے جو اَغْرَقَ کا مصدر ہے.اور اَغْرَقَ فِی الْمَائِ کے معنے ہوتے ہیں غَرَّقَہٗ اُس کو پانی میں ڈبو دیا.اور جب کہیں اَغْرَقَ الْکَأْسَ تو اس کے معنے ہوتے ہیں مَلَأَ ھَا اُس کو بھر دیا.اور جب کہیں
Page 108
اَغْرَقَ النَّازِعُ فِیْ الْقَوْسِ تو اس کے معنے ہوتے ہیں مَدَّھَا اُس کو خوب کھینچا اور جب کہیں کہ اَغْرَقَ النَّبْلَ تو اس کے معنے ہوتے ہیں اِذَابَلَغَ بِہٖ غَایَۃَ الْحَدِّ فِی الْقَوْسِ یعنی اُس نے تیر کو اتنے زور سے کھینچا کہ اُس کی نوک کمان کے ڈنڈے سے آملی.اور جب کہیں اَغْرَقَ فُلَانٌ فِی الشَّیْءِ تو اس کے معنے ہوتے ہیں بَالَغَ فِیْہِ وَاَطْنَبَ اُس نے کام کو حد تک پہنچا دیااور اُس میں اطناب اور طوالت سے کام لیا.مثلاً کوئی شخص بات شروع کرے اور وہ لمبی گفتگو کرتا چلا جائے تو اُس موقع پر یہ فقرہ استعمال کریں گے.اسی طرح جب کہیں اَغْرَقَ النَّاسُ فُلَانًا تواس کے معنے ہوتے ہیں کَثُرُوْا عَلَیْہِ فَغَلَبُوْہُ (اقرب) لوگوں نے جمع ہو کر اُس پر حملہ کر دیا اور اُسے مغلوب کر لیا.وَ النّٰزِعٰتِ غَرْقًاکے نو لغوی معنی گویاوَ النّٰزِعٰتِ غَرْقًا کے معنے ہو جائیں گے کہ (۱) کسی چیز کو اس کی جڑ سے خوب اچھی طرح اُکھیڑنے والی ہستیاں (۲) یا وہ گروہ جو اپنے کام کو اُس کی پوری انتہاء تک پہنچا دیتے ہیں (۳) یا حکامِ وقت کو معزول کر دینے والے گروہ جو اپنی تدبیر کو کمال تک پہنچا دیتے ہیں (۴)یا تیروں کو کھینچنے والی جماعتیں جو لڑائی میں تیروں کو اس قدر زور اور جوش سے کھینچتی ہیں کہ تیر کمانوں کی لکڑی تک پہنچ جاتے ہیں (۵) یا وہ جماعتیں جو کنوئوں میں سے پانی نکال نکال کر پانی پلاتی ہیں اور پورے زور سے پانی کھینچتی ہیں.(۶) یا وہ جماعتیں جو بعض کاموں سے پوری طرح رُک جاتی ہیں (۷) وہ جماعتیں جو اپنی روحانی یا جسمانی باپوں سے انتہائی طور پر مشابہت اختیا رکر لیتی ہیں (۸) یا وہ جماعتیں جن کے دلوں میں اپنے مقاصد میں کامیابی حاصل کرنے کی زبردست خواہش ہوتی ہے (۹)یا وہ جماعتیں جولوگوں کو کسی کام کی نہایت ہی جوش وخروش سے دعوت دیتی ہے.تفسیر.النّٰزِعٰتِ سے پہلے واؤ قسم کی ہے اَلنَّازِعَات کے شروع میں جو وائو آتا ہے یہ قسم کا ہے اور بعد کے وائو عطف کے ہیں.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم قسم کھاتے ہیں نَازِعَاتِ کی جو غرق ہو کر نزع کرتی ہیں.عربی زبان میں قسم کے لئے وائوؔ.با.ؔ تا.ؔ تین حروف آتے ہیں.اِن میں سے وائو کا زیادہ استعمال ہوتا ہے لیکن عربی زبان میں اصل حرفِ قسم با کوؔسمجھا جاتا ہے.چنانچہ کہا جاتا ہے اُقْسِمُ بِاللّٰہِ یعنی اُقْسِمُ کے ساتھ باء کو بھی ظاہر کر دیا جاتا ہے مگر یہ کبھی نہیں کہا جاتا کہ اُقْسِمُ وَاللّٰہِ یا اُقْسِمُ تَاللّٰہِ.اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قسم کیلئے اصل حرف باء ہے.لیکن کبھی باء کے بدلہ میں وائو بھی آجاتی ہے اور وائو کے بدلہ میں تاء آجاتی ہے گویا وائو اور تاء یہ دونوں باء کے تابع ہیں.قرآن مجید میں تمام اقسام جو شہادت کے رنگ میں آتی ہیں ان سے پہلے وائو استعمال ہوا ہے باء یا تاء استعمال نہیں ہوئے.اس سے قیاس ہوتا ہے کہ وائو کا حرف ایسی قَسمِ شہادت کے لئے جو اپنے سے ادنیٰ ہستی کی کھائی جائے زیادہ مناسب ہے.چنانچہ آیت زیرِ بحث میں بھی وَ النّٰزِعٰتِ غَرْقًا آتا ہے نہ کہ تَالنَّازِعَاتِ.
Page 109
قرآنی قسموں کی فلاسفی یہاں موقع کے لحاظ سے اگرچہ اس بحث کی جگہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ قسمیں کیوں کھاتا ہے.اس سے پہلے بہت سی سورتیںایسی گزر چکی ہیں جہاں یہ بحث آنی چاہیے تھی مگر چونکہ آخری پارے کی تفسیر پہلے شائع ہو رہی ہے.اس لئے جیسے سورۂ یونس سے پہلے مقطّعات کے متعلق بحث کی گئی ہے کیونکہ اس حصہ کی تفسیر سورۂ بقرہ سے پہلے شائع ہوئی ہے.یہاں بھی اس امر پر بحث کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قسم کیوں کھاتا ہے یا پھر یہ کہ اگر یہ قسم خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں تو کیا بندے کی طرف سے ہے؟ ادنیٰ تدبر سے معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ قسم بندے کی طرف سے نہیں ہو سکتی.کیونکہ اس کے بعد جو مضمون بیان ہوا ہے وہ انسان کی طرف سے نہیں کہا جاسکتا.ان قسموں کے بعد فرمایا گیا ہے یَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَۃُ اور یہ ایک پیشگوئی ہے اور پیشگوئی علمِ غیب سے ناواقف انسان کی طرف سے نہیں ہو سکتی.عالم الغیب ہستی ہی کی طرف سے ہو سکتی ہے.پس ان قسموں کو خدا تعالیٰ کی قسمیں ہی قرار دینا پڑے گا اور اس پر سوال پیدا ہو گا کہ خدا نے قسم کیوں کھائی یا کیوں وہ متعدد مقامات پر قسم کھاتا ہے؟ انسان تو اس لئے خدا تعالیٰ کی قسم کھا یا کرتا ہے کہ خدا تعالیٰ ایک بالا ہستی ہے اور انسان اس کے مقابلہ میں بالکل بے بس ہے وہ خدا تعالیٰ کو اپنے دعویٰ کی تائید میں گواہ کے طور پر پیش کرتا ہے اَور یہ کہتا ہے کہ اگر مَیں اُس کا نام گواہی کے طور پر یُوں ہی لیتا ہوں تو وہ طاقت رکھتا ہے کہ مجھے تباہ کر دے اور اگر وہ باوجود اس کا نام جھوٹے طور پر لے دینے کے مجھے تباہ نہ کرے تو سمجھ لو کہ وہ میرے سچے ہونے کی گواہی دیتا ہے.لیکن خدا کے اُوپر تو کوئی اَور ہستی نہیں جسے وہ اپنے دعویٰ کی سچائی کے ثبوت میں پیش کر سکتا ہو اور جب تمام چیزیں خدا تعالیٰ سے شان اور طاقت میں چھوٹی ہیں تو چھوٹی چیز کی قسم کھانے سے کیا فائدہ.ایسی قَسم کے تو کوئی معنے ہی نہیں ہو سکتے.انسان اگر قسم کھاتا ہے تو بڑی چیز کی کھاتا ہے لیکن خدا تعالیٰ سے بڑی تو اورکوئی ہستی نہیں پھر خدا تعالیٰ نے قسم کیوں کھا ئی ہے.قسم کھانے کا مطلب جیسا کہ اوپر اشارہ کیا گیا ہے انسان جب قسم کھاتا ہے تو اُس کی قسم کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کا حکم سچ بولنے کا ہے اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو اُس کا حکم توڑتا ہوں اور اُس کے غضب کو اپنے اُوپر بھڑکاتا ہوں اِس لئے میں خدا تعالیٰ کی قسم کھاکر کہتا ہوں کہ میں سچ بول رہا ہوں تا کہ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ میرے جھوٹ اور نافرمانی کی وجہ سے مجھے سزا دے.گویا انسان جب اللہ تعالیٰ کی قسم کھا تا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جھوٹ کے نتیجہ میں خدا تعالیٰ کا غضب بھڑکا کرتا ہے کیونکہ خدا جھوٹ کو ناپسند کرتا ہے ایسی حالت میں جب میں خدا کی قسم کھا کر کوئی جھوٹی بات کہتا ہوں تو گویا اُس کے غضب کو میں اَور بھی بھڑکاتا ہوں.کیونکہ اول خدا کا حکم تھا کہ میں سچ بولوں مگر میں نے خدا کے حکم کو توڑا اور سچ بولنے کی بجائے جھوٹ سے کام لیا.
Page 110
دوسرے ایک زائد بات یہ کی کہ میں نے یہ کہا کہ خدا اس بات کا گواہ ہے کہ میں سچ بول رہا ہوں.گویا ایک تو خدا تعالیٰ کا حکم توڑا کیونکہ خدا تعالیٰ کا حکم تھا کہ ہمیشہ سچ بولو مگر میں نے اس حکم کے خلاف جھوٹ بولا اور اس کی نافرمانی کی؟ دوسرے نہ صرف میں نے جھوٹ بولا بلکہ اس میں خدا تعالیٰ کو بھی شریک کرنا چاہا کہ وہ بھی گواہ ہے کہ میں سچ بول رہا ہوں.یہ بات ظاہر ہے کہ اگر انسان سے کوئی عام گناہ صادر ہو گا تو خدا تعالیٰ کی غیرت اُس کے خلاف اتنی نہیں بھڑکے گی جتنی اُس صورت میں بھڑکے گی جب وہ خدا تعالیٰ کو بھی اپنے گندے فعل میں شریک کرنا چاہے گا.اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ہر گناہ کے خلاف خدا تعالیٰ کی غیرت بھڑکتی ہے مگر گناہ گناہ میں فرق ہوتا ہے کسی پر اُس کی غیرت کم بھڑکتی ہے اور کسی پر اُس کی غیرت زیادہ بھڑکتی ہے.جب کوئی شخص اپنے گناہ میں خدا تعالیٰ کو بھی شریک کرنا چاہے گا تویہ لازمی بات ہے کہ اس پر خدا تعالیٰ کی غیرت زیادہ بھڑکے گی.اس کی ایسی ہی مثال ہے جیسے اگر کوئی شخص شراب پئے تو ہم کہیں گے کہ وہ بہت بُرا کرتا ہے لیکن اگر اُسے شراب سے منع کیا جائے اور وہ کہے کہ فلاں بزرگ بھی شراب پیتا ہے اور وہ بزرگ ایسا ہو جس کی عزت لوگوں کے دلوں میں ہو تو اس کے خلاف لوگوں کو اور زیادہ غصّہ آئے گا کہ ایک تو تم شراب پیتے ہو اور دوسرےؔ شراب کے گناہ میں ایک بزرگ کو بھی ملوّث کرنا چاہتے ہو.اسی طرح ہر گناہ خدا تعالیٰ کی ناراضگی کا موجب ہوتا ہے مگر جب کوئی جھوٹی قسم کھاتا ہے تو وہ اُس کی ناراضگی کو اور بھی بھڑکا تا ہے کیونکہ وہ خدا تعالیٰ کوبھی اپنے جھوٹ میں شریک کرتا ہے.قسم کے معنے خدا تعالیٰ کو اپنے فعل میں شریک کر نے کے ہیں قسم کے معنے درحقیقت خدا تعالیٰ کو اپنے فعل میں شریک کرنے کے ہوتے ہیں.پس اگر وہ سچی بات ہے جس پر کوئی شخص قسم کھاتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں.مثلاً وہ قسم کھا کر کہتا ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں اور واقعہ بھی یہی ہو کہ وہ نماز پڑھا کرتا ہو تو اس میں خدا تعالیٰ کی غیرت بھڑکنے کا کوئی سوال ہی نہیں.خدا تعالیٰ بہرحال جانتا ہے کہ وہ نماز پڑھا کرتا ہے اور جو کچھ کہتا ہے سچ کہہ رہا ہے.لیکن اگر وہ نماز نہیں پڑھتا اور کہتا ہے کہ خدا کی قسم! میں نماز پڑھا کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہو گا کہ وہ اپنے فریب اور دغا میں خدا تعالیٰ کو بھی شامل کرتا ہے اور جب وہ ایسا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی غیرت اُس کے خلاف بھڑک اٹھتی ہے.قسم ذریعہ تسلی گویا قسم کا منشاء یہ ہوتا ہے کہ سننے والوں کی تسلی ہو جائے.جب کوئی شخص کہتا ہے کہ میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے ایسا فعل کیا ہے تو خدا تعالیٰ تو اس کی سچائی کی شہادت اپنی زبان سے نہیں دیتا اور نہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قسم کے بعد اللہ تعالیٰ یوں کہے کہ ہاں میرا یہ بنداسچ بول رہا ہے لیکن باوجو د اس کے جو شخص قسم
Page 111
کھاتا ہے وہ بھی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اگر میں نے جھوٹی قسم کھائی تو خدا تعالیٰ کی گرفت میں آجائوں گا اور سننے والا بھی سمجھتا ہے کہ اگر اس نے جھوٹ بولا تو چونکہ اس نے اپنے جھوٹ میں خدا تعالیٰ کو بھی شریک کر لیا ہے اس لئے وہ اسے سزا دئے بغیر نہیں چھوڑے گا.پس قسم میں ایکؔ تو دوسروں کو اس بات کا یقین دلانا مدنظر ہوتا ہے کہ مجھے اپنی بات کی سچائی پر اس قدر کامل یقین ہے کہ میں خدا تعالیٰ کو بھی اپنے بیان کا گواہ بناتا ہوں گویا میرے علم اور خدا تعالیٰ کے علم میں جہاں تک اس بات کا تعلق ہے بالکل مطابقت ہے کوئی بات خلاف حقیقت میں نے بیان نہیں کی.دوسرےؔ سننے والوں کو تسلّی ہو جاتی ہے کہ اگر قسم کھانے والے نے خدا کو اپنے جھوٹ میں شریک کیا تو ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں خدا تعالیٰ خود اسے سزا دے گا.غرض یہ حکمت ہے جو قسموں میں پائی جاتی ہے ایک طرف انسان خدا تعالیٰ سے اپنے اتّحاد کا اظہار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس بارہ میں میرا علم اور خدا کا علم ایک ہی ہے مثلاً جب وہ کہتا ہے میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ زیدؔ لاہور گیا ہے تو اس کے دوسرے لفظوں میں یہ معنے ہوتے ہیں کہ خدا تعالیٰ جو علیم وخبیر ہے جو زمین وآسمان کے ذرّہ ذرّہ کے حالات کو جاننے والا ہے جس سے کوئی بات پوشید ہ نہیںاس بارہ میں اُس کا علم اور میرا علم ایک ہی ہے.دوسرےؔ سننے والوں کی تسلّی ہو جاتی ہے کہ اگر اُس نے افتراء سے کام لیا ہے تو اللہ تعالیٰ اُسے خود پکڑے گا اور جب پکڑے گا اُس وقت ہمیں بھی معلوم ہو جائے گا کہ اس شخص نے جھوٹ اور افتراء سے کام لیا تھا.گویا قسم میں دو چیزیں ہوتی ہیں.ایک ؔ خدا تعالیٰ کے علم کے ساتھ اپنے علم کو شریک کر نا اور کہنا کہ میرا علم اور خدا تعالیٰ کا علم اس بارہ میں ایک ہی ہے.دوسرےؔ خدا تعالیٰ کی سز ا کو چیلنج کرنا کہ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو میں اس بات کے لئے تیار ہوں کہ وہ مجھے پکڑے اور اپنے عذاب میں گرفتار کر ے.مگر خدا تعالیٰ پر تونہ کوئی حاکم ہے نہ اُس پر کسی کا حکم جاری ہے نہ اُسے کوئی سزا دے سکتا ہے اور جب نہ خدا تعالیٰ پر کوئی حاکم ہے نہ اُس پر کسی کاحکم جاری ہے اور نہ اُسے کوئی سزا دے سکتا ہے تو سوال یہ ہے کہ پھر اُس کے قسم کھانے میں کیا فائدہ مدنظر ہو سکتا ہے.جب کوئی انسان قسم کھا کر کہتا ہے کہ میں نے ایسا کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چونکہ میں نے خدا تعالیٰ کو بھی اپنے فعل میں شریک کر لیا ہے اس لئے اگر میں نے ایسا نہیں کیا تو وہ مجھے سزا دے گا.لیکن خدا تعالیٰ کو توکوئی سزا نہیں دے سکتا.پھر قسم میں اس امر کا اظہار ہوتا ہے کہ اس بارہ میں میرا علم اور خدا تعالیٰ کا علم یکساں ہے.مگر خدا تعالیٰ قسم کھاتا ہے تو اُس میں یہ حکمت بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ خدا تعالیٰ کا علم بہرحال غالب ہے دوسرے کے علم کو یکساں قرار دینے سے اُس کے بیان کو کوئی تقویت حاصل نہیں ہوتی.پس وہ کسی دوسرے علم کو اپنے علم کی شہادت کے طور پر پیش نہیں کر سکتا.پھر ایسی قسم کا نتیجہ ہی کیا نکلے گا
Page 112
جبکہ جس کی قسم کھائی گئی ہے اللہ تعالیٰ کے مقابلہ میں بے اختیا ر ہے اور اس کا علم خدا تعالیٰ کے علم کےمقابلہ میں ہیچ ہے.ایک طالب علم تو کہہ سکتاہے کہ جو مسئلہ میں نے بتایا ہے درست ہے جائو اُستاد سے پوچھ لو لیکن کبھی کوئی استاد یہ نہیں کرتا کہ جو مسئلہ میں نے بتا یا ہے وہ درست ہے جائو میرے شاگرد سے پوچھ لو.پس مخالف کہتا ہے کہ ایسی قسمیں بالکل فضول ہیں.ان کا وجود کلام الٰہی میں پایا جانا خلاف عقل ہے.قسم کا مفہو م عربی زبان میں اس اعتراض کا جوا ب دینے سے پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ قسم کا مفہوم کیا ہے.عربی زبان میں قسم کے لئے تین الفاظ استعما ل ہوتے ہیں (۱) حلف (۲)یمین(۳)قسم جو معنے قسم کے اوپر بیان کئے گئے ہیں وہ وہی ہیں جوعرفِ عام میں لئے جاتے ہیں لیکن قرآن مجید چونکہ عربی زبان میں ہے اس لئے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ عربی زبان میں حلف یمین اور قسم کا کیا مفہوم ہوتا ہے اور اُس مفہوم کے مطابق اللہ تعالیٰ کے قسم کھانے میں کیا حکمت ہے.قسم کا مفہوم ادا کرنے کے لئے عربی زبان میں تین الفاظ میں بتا چکا ہوں کہ عربی زبان میں قسم کے لئے تین الفاظ پائے جاتے ہیں حلف.یمین اور قسم.چنانچہ عربی زبان میں کہتے ہیں حَلَفَ بِاللّٰہِ حَلْفًا اور اس کے معنے وہ یہ کرتے ہیں اَقْسَمَ بِہٖ (اقرب) اُس نے خدا تعالیٰ کی قسم کھائی.جہاں تک ان معنوں کا تعلق ہے یہ کوئی زائد بات نہیں بتاتے صرف عُرفِ عام میں قسم کا جو مفہوم سمجھا جاتا ہے اُسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں اس لئے ہم حلف کے لفظ کو یا اُس کے اشتقاق صغیر و کبیر کے معنوں کو دیکھتے ہیںکہ وہ کیا ہیں تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ حلف کے معنوں میں کون کون سی بات پائی جاتی ہے.عربی زبان میں قسم کے لئے مختلف الفاظ کا استعمال اورا ن کا اشتقاق کے لحاظ سے آپس میں تعلق جہاں تک لفظِ حلف کا تعلق ہے اُس کے قریباً سارے اشتقاق خواہ وہ اشتقاق صغیر ہوں یا اشتقاق کبیر قَسم کے معنے دیتے ہیں سوائے اَلْحَلْفَاءُ کے جس کے معنے قسم کے نہیں.بلکہ حَلْفَاءُ ایک ایسی بوٹی کو کہتے ہیں جو پانی میں اُگتی ہے اور جس کے پتّوں کے کونے نوکدار اور تیز ہوتے ہیں (اقرب) اسی طرح حَلِیْف کا لفظ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے جس کے معنے ہر اُس چیز کے ہوتے ہیں جو دوسری سے جُدا نہ ہو چنانچہ لکھا ہے اَلْحَلِیْفُ کُلُّ شَیْءٍ لَزِمَ شَیْعًا فَلَمَ یُفَارِقْہُ ( اقرب) حَلِیْف کے دوسرے معنے اَلْحَدِیْدُ مِنْ کُلِّ شَیْ ئٍ کے ہوتے ہیں (اقرب) یعنی ہر ایسی چیز جو تیز اور دھار دار ہو.گویا حَلْفَاء وہ بوٹی ہوتی ہے جس کے پتوں کے کونے نوکدار اور تیز ہوتے ہیں.حَلِیْف وہ چیز ہوتی ہے جو کسی دوسری چیز سے چمٹی رہے اور حلیف اُس چیز کو بھی کہتے ہیں جو تیز اور دھار دار
Page 113
ہو.اس تشریح سے دو معنے ایسے نکل آئے جن سے حلف کے مفہوم میں فائدہ اُٹھایا جا سکتا ہے اوّلؔ تیز اور دھار دار ہونا دومؔ کسی چیز کا کسی دوسری چیز سے چمٹا ہوا ہونا.گویا جہاں بھی حاء.لام.اور فاء اکٹھے ہوں گے وہاں یہ دو معنے ضرور پائے جائیں گے (اول) کسی چیز کا دوسری چیز سے چمٹ جانا (دوم) اُس کا تیز اور دھار دار ہونا.اس کے بعد ہم حاء.لام.اور فاء کے دوسرے مرکبات کو لیتے ہیں جو پانچ ہیں یعنی (ا) حَفلؔ.(۲) لَحفؔ.(۳) لفحؔ.(۴) فحل (۵) فلحؔ.گویا حاء.فاء اور لام اکٹھے ہوجائیں تو حَفْلٌ بن جائے گا.لام.حاء.اور فاء اکھٹے ہو جائیں تو لحف بن جائے گا.لام،فائ اور حاء اکٹھے ہو جائیں گے تو لفحٌ بن جائے گا.فاء ، حاء اور لام اکھٹے ہو جائیں تو فحل بن جائے گا.اور فاء.لام.حاء اکٹھے ہوں جائیں تو فَلْحٌ بن جائے گا.یہ پانچوں قسم کے اشتقاق عربی زبان میں مستعمل ہیں.اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان حروف کےتغیرسے معنے کیا بنتے ہیں.یعنی جب حَاء، فَاء اور لَام اکٹھے ہوںتو اس کے معنے ہوتے ہیں اور جب لام، حاء اور فَاء اکٹھے ہوں تو اس کے کیا معنے ہوتے ہیں.سب سے پہلے ہم حَفْلٌ کو لیتے ہیں حَفْلٌ کے تمام مشتقات اجتماع اور کثرت پر دلالت کرتے ہیں چنانچہ حَفْلَۃٌ جلسہ اور اجتماع کو کہتے ہیں.اور اجتماع میں ایک دوسرے سے مل کر بیٹھا جاتا ہے یہی مفہوم حَلِیْف کا بھی تھا کیونکہ اس کے بھی یہی معنے تھے کہ کُلُّ شَیْءٍ لَزِمَ شَیْئًا فَلَمْ یُفَارِقْہُ (اقرب) ایک چیز جو دوسرے کے ساتھ مل گئی اور پھر اُس سے جدا نہ ہوئی.حَفْلٌ کے معنے بھی اکٹھے ہونے اور آپس میں جڑجانے کے ہیں(اقرب) اسی لئے جلسہ کو حَفْلَۃٌ کہاجاتا ہے کیونکہ وہاں بھی ایک دوسرے سے مل کر بیٹھا جاتا ہے.اسی طرح حَفْلٌ کسی کام کو اس کی حد تک پہنچا دینے کو بھی کہتے ہیں.چنانچہ کہا جاتا ہے اِحْتَفَلَ فِیْہِ اَیْ بَالَغَ (اقرب) یعنی اس نے اس کام کو اس کی حد تک پہنچا دیا.نیز کہتے ہیں اِحْتَفَلَ بَالْاَمْرِ اَیْ احْسَنَ الْقیَامَ بِہٖ (اقرب)یعنی کسی معاملہ کی پوری نگہداشت کی.اس میں بھی جڑنے اور دوسری چیز سے جدا نہ ہونے کا مفہوم پایا جاتا ہے.کیونکہ کسی کام کو اس کی حد تک وہی شخص پہنچا سکتا ہے جو اس کام کے ساتھ چمٹا رہے اور اُس سے الگ نہ ہو.گویا اس میں بھی جڑنے کے معنے آ گئے.اسی طرح اَحْسَنَ الْقِیَامَ بِہٖ کے بھی یہی معنے ہیں کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے اِدھر وہ کوئی کام شروع کرتے ہیں اور اُدھر اس کو چھوڑ دیتے ہیں گویا استقلال کا مادہ اُن میں نہیں ہوتا.لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں جو استقلال کے ساتھ اُس کام میں لگے رہتے ہیں گو یا وہ اپنے کام کے ساتھ جڑے رہتے ہیں اُس سے الگ نہیں ہوتے.اس میں بھی جُڑنے اور دوسری چیز سے الگ نہ ہونے کا مفہوم آگیا.دوسرا اشتقاق لَحْفٌ ہے.یہ بھی ایک دوسری چیز کو لپٹانے یا ملانے یا لگانے کے معنے دیتا ہے.اسی سے ہماری
Page 114
اُردو زبان کا لِحَاف نکلا ہے کیونکہ ہم اُس کو اوڑھ لیتے ہیں اور وُہ ساری رات ہمارے جسم سے چمٹا رہتا ہے.تیسرا اشتقاق لَفْحٌ ہے.اس کے معنے بھی چھونے کے ہوتے ہیں کہتے ہیں لَفَحَہٗ بِالسَّیْفِ: ضَرَبَہٗ بِہٖ (اقرب)یعنی اس کو تلوار سے مارا.اس میں دوسرے معنے بھی پائے جاتے ہیں یعنی وہ معنے جو نقصان اور ضرر سے تعلق رکھتے ہیں.اسی طرح کہتے ہیں لَفَحَتْہُ النَّارُ: اَحْرَقَتْہُ (اقرب) یعنی آگ نے اُس کو جلا دیا.لسان العرب والے کے نزدیک اس کے معنی یہ ہیں کہ اَصَابَتْ وَجْھَہٗ یعنی آگ لگی اور اُس نے دوسرے کے منہ کو جُھلسا دیا.گویا اس میں چھونے کے معنی بھی پائے جاتے ہیں اور ضرر کے معنے بھی پائے جاتے ہیں.لُفَّاحٌ ایک خوشبودار بُوٹی ہوتی ہے جس کو سُونگھا جاتا ہے (اقرب) گویا اس اشتقاق میں بھی لگنے اور چھونے اور ضرر پہنچانے کے معنے شامل ہیں.چوتھا اشتقاق فَحْلٌ ہے اور فَحْلٌ عربی زبان میں سانڈ کو کہا جاتا ہے جس سے بچہ لیا جاتا ہے (اقرب) اس میں بھی چھونے کے معنے پائے جاتے ہیں کیونکہ اُسے بچہ لینے کے لئے مادہ پر ڈالا جاتا ہے.راوی کو بھی فَحْل کہتے ہیں (اقرب) جس سے دوسرے لوگ روایتیں نقل کرتے ہیں کیونکہ وہ بھی ساتھ رہتا ہے اور دوسرے کو چمٹا رہتا ہے.فَحْلَۃٌ اُس عورت کو کہتے ہیں جو زبان دراز ہو (اقرب)جسے ذرا بھی کوئی بات کہہ دی جائے تو وہ پیچھے پڑ جائے.ہماری زبان میں بھی کہتے ہیں کہ پِچھا بھی چھڈ.یعنی تُو تو پیچھے ہی پڑ گیا ہے اپنی بات کوختم ہی نہیں کرتا.پس فَحْلَۃٌ اس عورت کو کہتے ہیں جو دوسرے کے پیچھے پڑ جائے اور ساتھ ہی وہ زبان دراز ہو.گویا اس میں بھی چمٹنے اور ضرر پہنچانے کے معنے پائے جاتے ہیں.ف ل ح اس کا آخری اشتقاق ہے جس سے ایک لفظ فَلَاح بنتا ہے.اس کے معنے کامیابی اور بامراد ہونے کے ہیں.اِن معنوں میں بھی ایک چیز کو اپنے ساتھ چمٹانے اور لگائے رکھنے کا مفہوم پایا جاتا ہے کیونکہ جو شخص اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے وُہ اُس کو اپنے پاس ہی رکھ لیتا ہے دوسرے کے پاس وہ اُس کو جانے نہیں دیتا.پھر فلح کے اشتقاق میں علاوہ کامیابی کے پھاڑنے کے بھی معنےپائے جاتے ہیں چنانچہ اسی اشتقاق سے فَلَّاح کا لفظ نکلا ہے جس کے معنےزمیندار کے ہیں جو زمین کو پھاڑتا ہے.ملّاح جو چپُّو سے کشتی کو چلاتا ہے اُس کو بھی اسی لئے فلاح کہہ لیتے ہیں کہ وہ پانی کو پھاڑ کر کشتی چلاتا ہے.اور یہ لفظ بھی اشتقاق اکبر کے طور پر ف لا ح کے معنوں پر دلالت کرتا ہے (اقرب) ان سب معنوں کو جب اکٹھا ملا کر دیکھا جائے تو اِن میں دو باتیں پائی جاتی ہیں.اوّل ایک چیز کا دوسری چیز سے چمٹ جانا یا ایک چیز کو دوسری سے جوڑنا جیسے حَلِیْف اُس کو کہتے ہیں جو دوسرے سے جدا نہ ہو.حَفْلَۃٌ اجتماع اور اکٹھے ہونے کوکہتے ہیں.لِحَافٌ اُس کو کہتے ہیں جو اُوپر آکر لپٹ جاتا ہے.لَفْحٌ شعلہ کے آچمٹنے کو کہتے ہیں.
Page 115
لُفَّاحٌ وہ بُوٹی ہے جسے سُونگھا جاتا یعنی ناک سے لگایا جاتا ہے.فَحْلٌ سانڈ کو کہتے ہیں جو مادہ پر سوار ہوتا ہے.فَحْلۃٌ اس عورت کو کہتے ہیں جو پیچھے پڑ جائے اور راوی بھی فَحْلٌ کہلاتا ہے کہ روایات یاد رکھنے کے لئے وہ ساتھ رہتا ہے.فَلَاح یعنی کامیابی کے بھی یہی معنے ہیں کہ انسان اپنے مطلب کو پالیتا ہے.گویا یہ سب معنے اکٹھا کرنے.جوڑنے اور ساتھ ملانے پر دلالت کرتے ہیں مگر ساتھ ہی ساتھ ایک اور معنے بھی پائے جاتے ہیں اور وہ آگ کے جلانے.تلوار مارنے اور زمین اور پانی کو پھاڑنے کے ہیں.گویا بعض اوقات کسی چیز کا دکھ دینا.جلانا یا چبھنا بھی اسی کے مفہوم میں شامل ہیں.یہ ددنوں معنے قَسم کے اُس عام مفہوم سے ملتے ہیں جو ہمارے ملک میں سمجھا جاتا ہے.اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عربی زبان میں جہاں بھی حاء اور لام اور فاء اکٹھے ہوں گے وہاں دو معنے ضرور پائے جائیں گے.ایک ؔ یہ کہ کسی چیز کو کسی دوسری چیز سے جوڑنا.اور دوسرےؔ یہ کہ کسی چیز کو پھاڑنا.جلانا اور نقصان پہنچانا.اِن دونوں معنوں کو اگر مدنظر رکھا جائے تو حلف کے یہ معنے ہوں گے کہ ایک کو دوسرے کے ساتھ ملانا.مگر اس طرح کہ بعض صورتوں میں قطع تعلق اور مخالفت کا بھی خطرہ ہو اور یہی غرض حلف کی ہوتی ہے.انسان قسم اس لئے کھاتا ہے کہ جس کی حلف اُٹھاتا ہے اُسے اپنا گواہ اور ساتھی قرار دیتا ہے اس شرط کے ساتھ کہ اگر اُس کا نام میںغلط طور پر لیتا ہوں تو وہ مجھے سزا دے یا میرے جھوٹ پر گواہ ہو.پس حلف کا مفہوم یہ ہوا کہ بندہ ایک طرف خدا کو اپنے ساتھ ملاتا ہے اور کہتا ہے خدا میرے ساتھ ہے اور اُس کا علم میری اس بات کی تصدیق کرتا ہے.اور دوسری طرف وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اگر میں نے جھوٹ بولا ہےتو میں پھاڑا جائوں.جِلایا جائوں.تباہ کر دیا جائوں.دوسرا لفظ قسم کے لئے عربی زبان میں قَسَم ہی ہے کہتے ہیں اَقْسَمَ بِاللّٰہِ اُس نے اللہ کی قسم کھائی یا اُقْسِمُ بِاللّٰہِ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں اِس کا ثلاثی قَسَم ہے اور اس کے تین معنے ہیں قَسَم الرَّجُلُ الْمَالَ: جَزَّأَہٗ اَوْ فَرَزَہٗ اَجْزَاءً (اقرب) اُس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دئیے یا اُسے تقسیم کیا.نیز کہتے ہیں قَسَم الدَّھْرُ الْقَوْمَ: فَرَّقَھُم (اقرب) قوم کو گردشِ زمانہ نے بکھیر دیا یا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا.پھر کہتے ہیں قَسَم فُلَانٌ اَمْرَہٗ: قَدَّرَہٗ وَنَظَرَ فِیْہِ کَیْفَ یَفْعَلُ اَوْ لَمْ یَدْرِمَا یَصْنَعُ فِیْہِ (اقرب) یعنی جب یہ کہیںکہ قَسَم فُلَانٌ اَمْرَہٗ تو اس کے معنے یہ ہوتے ہیں کہ اُس نے اپنے کام کی تقسیم کی.اُس کا اندازہ کیا اور ا س کے متعلق غور کیا کہ اُسے وہ کس طرح کرے یا وہ شک میں پڑ گیا کہ اس کام کو کس طرح سرانجام دے.عربی زبان میں قسم کے لئے استعمال ہونے والے الفاظ کی آپس میں معنی کی شرکت میرے
Page 116
نزدیک اَقْسَمَ بِا للّٰہِ کے معنے حَلَفَ بِہٖ کے ہی ہیں اور چونکہ اَقْسَمَ کے اور کوئی معنے عربی میں استعمال نہیں ہوئے اس لئے ثلاثی مجرد سے ہی اس کے معنوں کی حقیقت معلوم کرنی پڑے گی اور چونکہ اس کا فعل ثلاثی مجرد متعدی ہے اس لئے باب افعال کا ہمزہ سلب کے معنوں کے لئے زیادہ موزوں ہوگا جو اس باب کے ہمزہ کے مختلف معنی میں سے ایک معنے ہیں یعنی جو قَسَمَ کے معنے تھے وہ اَقْسَمَ بِاللّٰہ میں آکر سلبی صورت اختیار کر لیں گے وہاں اُس کے معنے تھے ٹکڑے کر دیا یابکھیر دیا.اور یہاں یہ معنے ہوں گے کہ اختلاف دور کر دیا اور ٹکڑوںکو ملا دیا.گویا ملانے کے معنے آگئے جو حلف کے معنوں سے مل جاتے ہیں.اسی طرح قَسَمَ فُلَانٌ اَمْرَہٗ کے معنے یہ تھے کہ وہ شک اور تردّد میں پڑ گیا.ایسے شک اور تردّد میں کہ لَمْ یَدْرِ مَایَصْنَعُ فِیْہِ اُسے کچھ معلوم نہ ہو سکا کہ وہ اس بارہ میں کیا کرے.لیکن اَقْسَمَ کے معنے ہوں گے اُس نے شک کو دور کر دیا گویا ازالۂ شک کرنے والی چیز بن گئی.یہ معنے بھی حلف والے معنوں سے مل جاتے ہیں کیونکہ حلف کے ذریعہ انسان دوسرے کے تردّد کو دُور کرتا اور یقین دلاتا ہے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ بالکل درست ہے اور میری اس بات پر خدا بھی گواہ ہے.گویا ہمزہ کو اگر ہم سلبیہ مانیں تو حلف کے معنوں سے اس کے معنے بالکل مل جاتے ہیں.حلف میں بھی ملانے اور اکٹھا کر دینے کے معنے تھے اور اس میں بھی ٹکڑوں کو ملانے اور اختلاف کودُور کرنے کا مفہوم شامل ہے اسی طرح وہاں بھی تردد کو دور کرنے کا مفہوم تھا اور یہاں بھی یہی مفہوم ہے کہ اُس نے تردّد دُور کر دیا.تیسرا لفظ قسم کے لئے عربی زبان میں یَمِیْن ہے لیکن اس لفظ کو قسم کے لئے اس لئے استعمال نہیں کرتے کہ اس میں قسم کی طرف کوئی معنوی اشارہ پایا جاتا ہے بلکہ یَمِیْن کا لفظ اس لئے قسم کی جگہ استعمال کیا جاتا ہے کہ عرب لوگ قسم کھا کر جب معاہدہ کرتے تھے تو ایک دُوسرے کے دائیں ہاتھ کو چُھوتے تھے.پس چونکہ ایسے موقع پر اَیَامَن (یمین کی جمع ہے)ملائے جاتے تھے اس لئے قسم کے لئے بھی یمینؔ کا لفظ استعمال ہونے لگا(لسان)گویا یمینؔ کالفظ صرف قسم کے ایک ذریعہ کی طرف اشارہ کرتا ہے اس کے لئے لغت موضوع نہیں ہے.پس قسم کے بارہ میں لغت کی شہادت صرف حلف اور قَسم کے لفظوں سے ملتی ہے اور جیسا کہ میں اُوپر بتا آیا ہوں اِن دونوں لفظوں سے یہ شہادت ملتی ہے کہ حلف اور قسم کے لفظوں کی غرض مشترک اتحاد پیدا کرنا.شک کودُور کر نا سزا دینا اور قطع کرنا ہے.یعنی ایک طرف قسم کے ذریعہ انسان اللہ تعالیٰ سے اتحاد پیدا کرتا ہے او رکہتا ہے کہ اس معاملہ میں میرا علم اور خدا تعالیٰ کا علم ایک ہی ہے اور دوسری طرف وہ یہ بات پیش کرتا ہے کہ اگر میں نے یہ بات غلط کہی ہے تو اللہ تعالیٰ کی سزا مجھ پر نازل ہو.پس حلف کی غرض عربوں کے نزدیک یہ ٹھہری کہ جس سے ایک وجود
Page 117
دوسرے وجودسے اپنا اتحادثابت کر کے اُسے اپنے سچے ہونے کی دلیل قرار دیتا ہے اور اُس میں غلط ہونے کی صورت میں قطع و عذاب کا مطالبہ کرتا ہے.قسم خدا کی طرف سے نازل ہونے والے کلام کے لئے خدائی کلام ہونے کا ایک ثبوت اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ان معنوں کے رُو سے خد اتعالیٰ کے لئے حلف اٹھانی جائز ہو سکتی ہے یا نہیں.اور کیا جب خدا تعالیٰ کسی چیز کی قسم کھائے تو یہ معنے وہاں چسپاں ہو سکتے ہیں؟ سو ہم دیکھتے ہیں کہ گو جو کچھ خدا تعالیٰ کہے اس کے انکار کی کسی انسان کو گنجائش نہیں ہو سکتی کیونکہ ہم مانتے ہیں کہ خدا تعالیٰ ہے اور جب وہ ہمیں کہتا ہے کہ بات یوں ہے تو ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے لازمًا ہمیں ماننا پڑے گاکہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے.لیکن ایک اور سوال ہے جس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگ اس مقام پرٹھوکر کھا جاتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ وراء الوراء ہے وہ ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر نہیں آسکتا.یہ نہیں ہوا کہ آسمان پھٹا ہو اور خدا تعالیٰ نے یہ کہا ہو کہ فلاں بات میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی تھی یا فلاں بات میں نے موسیٰ ؑسے کہی تھی یا فلاں بات میں نے عیسیٰ ؑسے کہی تھی یا فلاں بات میں نے زرتشت سے کہی تھی یا فلاں بات کرشن ؑسے کہی تھی.حضرت نوح ؑ آئے تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ خدا تعالیٰ نے مجھے ایسا کہا ہے.حضرت ابراہیم ؑ آئے تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ خدا نے مجھ سے ایسا کہا ہے.حضرت موسیٰ ؑ آئے تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ خدا نے مجھ سے ایسا کہا ہے حضرت عیسیٰ ؑ آئے تو انہوں نے بھی یہی کہا اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ خدا تعالیٰ نے مجھ سے ایسا کہا ہے مگر اُن کے مخاطبین نے اپنی آنکھوں سے خدا تعالیٰ کو نہیں دیکھا.اُن کے سامنے بات کرنے والا انسان ہی ہوتا تھا خدا تعالیٰ نہیں ہوتا تھا اور چونکہ خدا تعالیٰ نظر نہیں آتا اس لئے گو خدا تعالیٰ کی بات کا انکار نہیں ہو سکتا مگر اس کی طرف سے بھیجا ہوا کلام ضرور ثبوت کا محتاج ہوتا ہے.پس بے شک خدا تعالیٰ کو اپنی بات منوانے کے لئے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں مگر اُس کے کلام کو ایسے ثبوت کی ضرورت ہے.کیونکہ لوگ اس کلام کو براہ راست اللہ تعالیٰ کے منہ سے نہیں سنتے بلکہ ایک اپنے جیسے انسان کے منہ سے سنتے ہیں اس لئے یہ کہنا کہ خدا تعالیٰ کو قسم کی کیا ضرورت ہے محض ایک دھوکا ہے اگر مخاطب یہ بھی مان لیں کہ اس کلام کو سننے والا مانتا ہے کہ وہ خدا کا کلام ہے تو بھی اُس مدعی یا یہ یقین ہر سننے والے کو تو یقین نہیں دلا سکتا.مثلاً میں قرآن مجید پر کامل ایمان رکھتا ہوں میرے سامنے اگر بغیر قسم کے بھی قرآن مجید کوئی بات پیش کرے تو میں کہوں گا کہ ہاں بالکل درست ہے مجھے اس کی صداقت پر پورا ایمان ہے لیکن جو شخص قرآن مجید کو نہیں مانتا اُس کو تو ثبوت کی ضرورت ہے وہ بغیر کسی ثبوت کے کس طرح تسلیم کر لے گا کہ جو بات اُس کے سامنے پیش کی
Page 118
جارہی ہے وہ خدا تعالیٰ نے ہی کہی ہے کسی انسان نے اپنے پاس سے نہیں بنا لی.اگر اس قسم کا ثبوت خدائی کلام میں موجود نہ ہو تو اس کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہو کہ صادق اور کاذب مدعی میں کوئی مابہ الامتیاز نہ رہے گا اور لوگ اسی دھوکا میں گرفتار رہیں گے کہ ہمارے سامنے جو مدعی کھڑا ہے اس پر خدا تعالیٰ کی طرف سے کلام نازل ہوتا ہے یا یہ اپنے پاس سے بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کر دیتا ہے پس اس قسم کا ثبوت صرف اس لئے ضروری نہیں کہ بعض طبائع ایسی ہوتی ہیں جو بغیر اس امر پر تسلّی پانے کے کہ اس کلام کے پیش کرنے والے کو خود بھی اپنے الہام پر کامل یقین ہوتا ہے ایمان لانے کے لئے تیار نہیں ہوتیں بلکہ اس لئے بھی ضروری ہے کہ لوگوں کو یہ یقین ہو جائے کہ یہ خدا کا ہی کلام ہے اور اس کے متعلق جھوٹ سے کام نہیں لیا گیا.اگر بغیر دلیل اور ثبوت کے الٰہی کلام پیش کر دیا جائے اور جب کوئی ثبوت مانگے تو اُسے کہہ دیا جائے کہ خدائی کلام کے متعلق کسی ثبوت کی کیا ضرورت ہے کیا یہ بات کم ہے کہ میں کہہ رہا ہوں خدا تعالیٰ نے یہ کلام نازل کیاہے توکل کوئی جھوٹا مدعی کھڑا ہو جائے گا اور وہ بھی کہنا شروع کر دے گا کہ مجھے خدا تعالیٰ نے اس اس طرح کہا ہے.تب لوگ گھبرائیں گے کہ ہم کیاکریں کس کو مانیں اور کس کو ردّ کر یں یہ بھی کہتا ہے کہ مجھے خدا تعالیٰ نے کھڑا کیا ہے اور وہ بھی کہتا ہے کہ مجھے خدا تعالیٰ نے کھڑا کیا ہے ہم اس کی بات مانیں یا اس کی بات مانیں.پس چونکہ صادق اور کاذب مدعیان میں اس طرح کوئی مابہ الامتیاز نہیںرہ سکتا تھا اس لئے خدا تعالیٰ نے جھوٹے مدعیان نبوت کے فتنوں کو باطل کرنے اور دنیا پر ان کا جھوٹ ظاہر کرنے کے لئے اپنے اُوپر یہ واجب کر لیا ہے کہ وہ خود اپنے کلام کی سچائی کا ثبوت پیش کیا کرے گا.اگر حضرت ابراہیم یہ کہتے کہ جب میں کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ ایساکہہ رہاہے تو تم کیوں نہیں مانتے.یا حضرت موسی ٰ ؑ کہتے کہ تمہیں کسی ثبوت کی کیا ضرورت ہے میں جو کہہ رہا ہوں کہ خدا تعالیٰ مجھ سے ہم کلام ہوا اور اُس نے مجھ سے یہ یہ بات کی یا حضرت عیسیٰ ؑ کہتے ہیں کہ مجھ سے کسی ثبوت مانگنے کی کیا ضرورت ہے میں جو کہہ رہا ہوں کہ خدا مجھ سے بولا اور اُس نے مجھے یہ پیغام دیا.یا اگر یہی طریق حضرت زرتشت ؑ اختیار کرتے یہی طریق حضرت کرشن ؑ اختیا رکرتے یہی طریق حضرت رامچندر اختیار کرتے تو لوگ اس قدر ڈر جاتے کہ جو شخص بھی ان کے زمانہ میں مدعی بن جاتا اُسے مان لیتے اور اُس سے کسی ثبوت کا مطالبہ نہ کرتے اور چونکہ جھوٹے مدعی ہر زمانہ میں ہو سکتے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ جھوٹ پھیل جاتا اور صداقت مشتبہ ہو جاتی.پس خدا تعالیٰ نے اس فتنہ کو روکنے کے لئے اپنے کلام کی صداقت کا ثبوت مہیا کرنا اپنے اوپر واجب کر لیا ہےتاکہ جب کوئی کہے کہ اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ یہ کلام خدا تعالیٰ نے نازل کیا ہے تو فوراً اس کے سامنے ثبوت پیش کر دیا جائے اور کہہ دیا جائے کہ یہ یہ ثبوت ہیں جو اس بات کی دلیل ہیں کہ یہ خدا تعالیٰ کا کلام ہے کسی انسان کا بنایا ہوا کلام نہیں.پس چونکہ
Page 119
کاذب اور صادق میں امتیاز کرنا ضروری تھا اس لئے خدا تعالیٰ کا کوئی ایسا ثبوت پیش کرنا جس سے یہ ثابت ہو کہ وہ کلام جو اس کی طرف منسوب کر کے دنیا کے سامنے پیش کیا جاتا ہے درست ہے یا نہیں اس کی شا ن کے خلاف نہیں بلکہ اُس کی شانِ رحیمیت کا عین تقاضا ہے.وہ شخص جو خدا تعالیٰ کی طرف ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اگر وہ اپنے اُس کلام کی صداقت کا کوئی ثبوت پیش نہ کرے جسے وہ خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کرتا ہے بلکہ اگر اُسے کہا جائے کہ کوئی ثبوت اپنی سچائی میں پیش کرو تو وہ اس بات کو خدا تعالیٰ کی ہتک قرار دینے لگے تو نظام عالم پر تباہی آجائے.روز کوئی نہ کوئی مدعی کھڑا ہو جائے اور خدا تعالیٰ کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کرنا شروع کردے ا ِسی لئے خدا تعالیٰ نے یہ واجب کر لیا ہے کہ وُہ اپنے کلام کی سچائی کے ثبوت میں تائیدی شہادات پیش کیا کرے ورنہ کمزور لوگوں کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ رہے.پس ا للہ تعالیٰ کا ایسے ثبوت پیش کرنا اس کی شان کے خلاف نہیں بلکہ اس کی گواہی اپنے کلام کی سچائی کے لئے نہایت ہی ضروری ہے.اس لئے بھی کہ بندوں پر ثابت ہو جائے کہ وہ خدا کا کلام تھا اور اس لئے بھی کہ کوئی جھوٹا آدمی یہ جرأت نہ کرے کہ وہ بغیر کسی ثبوت کے خدا تعالیٰ کی طرف باتیں منسوب کرنے لگ جائے.جب یہ بات ثابت ہو گئی تو اب اس امر کے تسلیم کرنے میں کوئی روک نہیں ہو سکتی.کہ کوئی ایسا ثبوت جو حلف کے مشابہ ہو یقیناً ایک بہت بڑا ثبوت کلام الٰہی کی صداقت کا ہو گا.اور خدا تعالیٰ کا اپنے کلام کی تائید میں کسی ایسی دلیل کا پیش کرنا اس کی شان کے خلاف نہ سمجھا جائے گا بلکہ عین ضروری ہو گا.کسی کلام کی صداقت کا سب سے بڑا ثبوت حلف ہی ہوتا ہے جب ہم یہ ثابت کر چکے ہیں کہ اپنے کلام کی صداقت کا ثبوت خدا تعالیٰ کو بھی پیش کرنا چاہیے تو اب سوال یہ ہے کہ صداقت کا ثبوت سب سے بڑا کون سا ہوتا ہے؟ دنیا میں صداقت کاسب سے بڑا ثبوت حلف کو سمجھا جاتا ہے بلکہ آخری فیصلہ حلف پرہی قرار پاتا ہے کیونکہ بعض طبائع ایسی ہوتی ہیں جنہیں حلف کے بغیر اور کسی بات سے اطمینان ہی نہیں ہوتا.وہ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ فلاں شخص نیک ہے وہ یہ بھی یقین رکھتے ہوں گے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا مگر ساتھ ہی اُن کے دلوں میں یہ شبہ بھی ہو گا کہ کہیںیہ سب کچھ ڈھکونسلہ ہی نہ ہو کہ آسمان سے فرشتے اُترتے اور اللہ تعالیٰ کا کلام لاتے ہیں یا اللہ تعالیٰ بالمشافہ کسی شخص سے گفتگو کر سکتا ہے.لیکن جب کوئی قسم کھا لیتا ہے توان کو تسلی ہو جاتی ہے اور وہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ صرف ڈھکو نسلہ نہیں بلکہ مشاہدہ اس کی تائید میں ہے.اگر مشاہدہ اس کی تائید میں نہ ہوتا تو یہ قسم کیوں کھاتا.قرآن کی صداقت کو ثابت کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ کا قسم کھانا پس شبہ کو دور کرنے والی آخری چیز حلف ہی ہے اور جب شُبہات کو دُور کرنے کا خدا تعالیٰ نے حلف کو ایک قطعی اور یقینی ذریعہ قرار دیا ہوا ہے تو خدا تعالیٰ
Page 120
کا کلام جوسب سے زیادہ دلائل کا حقدار ہوتا ہے اگر اس دلیل کو ترک کر دے اور یہ ثبوت اپنی تائید میں پیش نہ کرے تو وُہ یقیناً ایک مفید اور ضروری پہلو کو ترک کرنے والا قرار پائے گا اور دنیا کے ایک حصہ کو جس کا حلف کے بغیر اور کسی بات سے اطمینان نہیں ہوتا غیر مطمئن رکھنے والا سمجھا جائے گا.اس اعتراض کا جواب کہ گو حلف قرآن مجید خدا تعالیٰ کی طرف منسوب ہے لیکن اس کے کھانے والے تو آنحضرت صلعم ہی ہیں اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ گو حلف خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کی گئی ہو مگر قسم کھانے والا تو وہ انسان ہی ہو گا جو اس کلام کو پیش کرتا ہے اس صُورت میں اسے کلام الٰہی کی سچائی کا ثبوت کس طرح سمجھا جا سکتا ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ بے شک حلف کو خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کیا گیا ہو گا اور بے شک حلف کھانیوالا بھی ایک انسان ہی ہوگا جو اس کلام کو پیش کرتا ہے لیکن اگر وہ جھوٹا ثابت ہو گا تو وہ قسم کس کے خلاف پڑے گی یقیناً اسی انسان کے خلاف پڑے گی جس نے اس قسم کو خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کیا.مثلاً زید کہتا ہے کہ مجھے خدا تعالیٰ نے ایسا کہا اور زیدبھی کہتا ہے کہ خدا تعالیٰ قسم کھا کر کہتا ہے کہ یہ بات سچی ہے.اب اگر وہ اپنی اس بات میں جھوٹا ہے اور اُسے خدا تعالیٰ نے کوئی بات نہیں کہی تو اُس قسم کی ذمہ واری کس پر عائد ہو گی؟اُسی پر ہو گی جس نے خدا تعالیٰ پر جھوٹ بولا اور جھوٹی قسم کھا کر لوگوں کو دھوکا دیتا رہا اور جب اُسی پر اس کی ذمہ واری ہو گی تو جب وہ الٰہی گرفت میں آئے گا سب لوگوں کو پتہ لگ جائے گا کہ وہ ایک جھوٹا انسان تھا جس نے افتراء سے کام لیا اور جس کے نتیجہ میں وہ الٰہی عذاب میں گرفتار ہو گیا.پس بنی نوع انسان کے دلوں کو یقین دلانے اور اُن کے شکوک و شبہات کو دُور کرنے کے لئے ضرور کوئی ایسا طریق ہونا چاہیے تھا جس سے ان کی تسلی ہو جاتی اور اسی وجہ سے قرآ ن کریم میں قسمیں کھائی گئی ہیں ان قسموں کے متعلق دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں (۱) یا تو کوئی شخص یہ تسلیم کرے گا کہ یہ قسمیں خدا تعالیٰ نے ہی کھائی ہیں کسی انسان نے نہیں کھائیں.اور جب وہ ان قسموں کو خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کرے گا تو یہ لازمی بات ہے کہ وہ کلام الٰہی کی صداقت پر بھی ایمان رکھے گا.(۲) یا پھر اس کا یہ عقیدہ ہو گا کہ یہ قسمیں خدا نے نہیں کھائیں بلکہ محمد رسول اللہ صلے اللہ علیہ وآلہٖ وسلم نے کھائی ہیں تب بھی وہ یقین رکھے گا کہ اگر انہوں نے نعوذ باللہ جھوٹی قسمیں کھائی ہیں تو خدا تعالیٰ اُن کو سزا دے گا.گویا اس دلیل کی جو غرض تھی وہ بہرحال پوری ہو جائے گی.اگر کسی شخص نے قرآن کریم کو خدا تعالیٰ کا کلام مان لیا تو اُس کے لئے کسی حلف یا تائیدی ثبوت کی ضرورت نہیں.وہ یقین رکھے گا کہ جس قدر قسمیں کھائی ہیں خدا تعالیٰ نے ہی کھائی ہیں اور اگر وہ سمجھے گا کہ یہ قسمیں خدا تعالیٰ نے نہیں کھائیں بلکہ محمد رسول اللہ صلے اللہ علیہ وآلہٖ وسلم نے نعوذباللہ خدا تعالیٰ پر افتراء کیا ہے تب بھی اس کا دل مطمئن ہو
Page 121
جائے گا.اور وہ سمجھے گا کہ محمد صلے اللہ علیہ وآلہٖ وسلم نے چونکہ (نعوذ باللہ من ذالک) جھوٹی قسمیں کھائی ہیں اس لئے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں پکڑے اور سزا دے.اس کے بعد اِن قسموں کے نتائج اُس پر خود ظاہر کر دیں گے کہ حقیقت کیا ہے.بہرحال حلف کلام الٰہی کی صداقت کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے.اور گو حلف کو خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کیا گیا ہو.مگر چونکہ جھوٹے کلام کی صورت میں قسم کھانے والا وہی انسان ہو گا جو اس کلام کو پیش کرتا ہے.اس لئے وہ قسم اس کے خلاف پڑے گی اور اس طرح ظاہر ہو جائے گا کہ حقیقت کیا تھی.صداقت کس طرف تھی اور دھوکہ و فریب کس طرف تھا.دوسرے وہی حلف حلف کہلا سکے گی جو حلف کی غرض پوری کرتی ہو.اور حلف کی غرض یہی ہوتی ہے کہ دوسرے وجود سے اپنا تعلق بتا کر اُسے بطور شاہد پیش کیا جاتا ہے اور اِن معنوں سے خدا تعالیٰ بھی حلف اٹھا سکتا ہے کیونکہ حلف کی ایک غرض یہ ہوتی ہے کہ قسم کھا کر دوسرے کو یقین دلایا جاتا ہے کہ اس بارہ میں فلاں اور مَیں دونوں ایک ہی بات کہتے ہیں.جب کوئی کہتا ہے خدا تعالیٰ کی قسم! فلاں بات اس طرح ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ بھی جانتا ہے کہ یہ بات اس طرح ہے.اور میں بھی جانتا ہوں کہ یہ بات اس طرح ہےاور اگر کسی اورچیز کی گواہی اپنی تائید میں پیش کی جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فلاں چیز بھی اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ میںجو کچھ کہہ رہا ہوں وہ بالکل درست ہے.اس طرح اُس چیز کی گواہی بتا دیتی ہے کہ جو کچھ کہا گیا ہے وہ غلط ہے یا درست.خدا تعالیٰ چونکہ لوگوں کی نگاہوں سے مخفی ہے اس لئے جب وہ کسی چیزکو بطور گواہ پیش کرے گا تو اُس چیز کی گواہی صداقت یا عدم صداقت کو بالکل ظاہر کر دے گی.اگر وہ چیز گواہی دے دے گی تو ثابت ہو جائے گا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ کہا گیا ہے واقعہ میں وہ اُسی نے کہا ہے اور اگر وہ چیز گواہی نہیں دے گی تو ثابت ہو جائے گا کہ خدا تعالیٰ کی طرف غلط بات منسوب کی گئی ہے پس خدا تعالیٰ کے قسم کھانے کے معنے یہ ہوں گے کہ وہ اس چیز یا چیزوں کو جن کی وہ حلف اٹھاتا ہے اپنے دعویٰ کی صداقت کے لئے بطور گواہ پیش کرتا ہے اگر وہ اشیاء گواہی دے دیں گی تو معلوم ہو جائے گا کہ خدا تعالیٰ کی طرف وہ کلام سچے طورپر منسوب کیا گیا ہے اور اگروہ گواہی نہیں دیں گی تو ثابت ہو جائے گا کہ وہ کلام جھوٹے طور پر خدا تعالیٰ کی طرف منسوب ہوا ہے.مثلاً خدا تعالیٰ کے کلام میں اگر یہ آجائے کہ فلاں بات کی صداقت پر پہاڑ گواہی پیش کریں گے تو یہ بات بالکل صاف ہو جائے گی اگرپہاڑ گواہی دے دیں گے تو ثابت ہو جائے گا کہ یہ بات خدا تعالیٰ نے ہی کہی تھی کیونکہ پہاڑوں سے گواہی دلوانا کسی انسان کے اختیار میں نہیں خدا ہی اُن سے گواہی دلوا سکتا ہے.اور اگر وہ گواہی نہیں دیں گے تو کلام کا جھوٹا ہونا ثابت ہو جائے گا
Page 122
اسی طرح اگر خدا تعالیٰ کے کلام میں آجائے کہ فلاں بات کی صداقت پر دریا گواہی دیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ دریا اُس بات کی صداقت میں اپنی گواہی پیش کرتے ہیں یا نہیں اگر وہ گواہی دے دیں گے تو ثابت ہو جائے گا کہ خدا تعالیٰ نے ہی وہ بات کہی تھی اور اگرو ہ گواہی نہیں دیں گے تو ثابت ہو جائے گا کہ وہ خدا تعالیٰ کا کلام نہیں تھا بلکہ جھوٹے طور پر اُس کی طرف منسوب کیا گیا تھا کیونکہ کوئی انسان یہ طاقت نہیں رکھتا کہ وہ کسی پہاڑ سے گواہی دلوا سکے یا کسی دریا کو گواہ بنا سکے.یہ سب چیزیں خدا تعالیٰ کے قبضہ و تصرف میں ہیں اور وہی طاقت رکھتا ہے کہ اُن سے گواہی لے کر دُنیا کے سامنے پیش کرے.خدا تعالیٰ کی بات کے لئے مخلوق کے گواہی دینے کا مطلب اگر کہا جائے کہ خدا تعالیٰ کی بات کو مخلوق کی گواہی سے کس طرح ثابت کیا جا سکتا ہے تو اس کا جوا ب وہی ہے جو اُوپربیا ن ہو چکا ہے کہ الٰہی کلام کے بارہ میں یہ سوال نہیں ہوا کرتا کہ آیا خدا تعالیٰ نے سچ کہا ہےیا نہیں بلکہ سوال یہ ہوا کرتا ہے جو بندہ اُس کلام کو پیش کر رہا ہے وہ خدا تعالیٰ پر سچ بول رہا ہے یا جھوٹ.پس یہ بحث ہی نہیں ہوتی کہ خدا تعالیٰ سچ کہہ رہا ہے یا نہیں.بلکہ بحث یہ ہوا کرتی ہے کہ خدا تعالیٰ کا نمائندہ ہو نے کا مدعی انسان جو کچھ کہہ رہا ہے وہ سچ ہے یا نہیں.پس وہ دلیل جو مخلوق کی شہادت کی خدا تعالیٰ کی طرف سے پیش کی جائے گی وہ اس امر کو ثابت کر دے گی کہ مدعی جو کچھ کہہ رہا تھا سچ کہہ رہا تھا اور اُس کا پیش کردہ کلام فی الواقعہ خدا تعالیٰ کی طرف سے تھا اور اس لئے وہ شخص سچا ہے پس مخلوق نے خدا تعالیٰ کو سچا ثابت نہیں کیا بلکہ اُس انسان مدعی کو سچا ثابت کیا جو خدا تعالیٰ کی طرف ایک کلام منسوب کر رہا تھا جب کسی پیشگوئی کے مطابق دریا گواہی دینے لگ جائیں یا پہاڑ گواہی دینے لگ جائیں یاسورج اور چاند گواہی دینے لگ جائیں اور فرض کرو کہ ان پیشگوئیوں کا ذکر کرشن کے کلام میں آتا ہو تو دریائوں اور پہاڑوں اور سورج اور چاند کی گواہی اس بات کو ثابت نہیں کرے گی کہ خدا تعالیٰ سچا ہے بلکہ اس بات کو ثابت کرے گی کہ کرشن جی نے جھوٹ نہیں بولا بلکہ اُس نے خدا تعالیٰ کی طرف جس کلام کو منسوب کیا تھا وہ خدا تعالیٰ کا ہی کلام تھا یا اگر حضرت ابراہیم ؑکی صداقت میں پہاڑ اور دریا گواہی دینے لگ جائیں تواس کا یہ نتیجہ نہیں نکالا جائے گاکہ چونکہ ان چیزوں نے گواہی دیدی ہے اِس لئے خدا تعالیٰ سچا ہے بلکہ نتیجہ یہ نکلے گا کہ ابراہیم ؑسچ کہہ رہا تھاکہ اُسے خدا تعالیٰ نے یہ یہ باتیں کہی ہیں یا جب حضرت موسیٰ ؑ کی پیشگوئی میں ذکر آ جائے کہ پہاڑ اور دریا گواہی دیں گے اور وہ واقعہ میں گواہی دے دیں تو اُن کی گواہی سے یہ ثابت نہیں ہو گا کہ خدا تعالیٰ سچا ہے بلکہ یہ ثابت ہو گا کہ موسیٰ ؑ نے اپنے خدا پر جھوٹ نہیں بولا بلکہ جو کچھ کہا سچ کہا.یا اگر رسول کریم صلے اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کی تائید میں پہاڑ اور دریا اور دنیا کی اور چیزیں گواہی دینے لگ جائیں تو اس کے
Page 123
یہ معنے نہیں ہوں گے کہ خدا تعالیٰ ان چیزوں کی گواہی کا محتاج تھا بلکہ اس کے صرف یہ معنے ہوں گے کہ محمد رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ اپنی صداقت کے لئے ان گواہیوں کا محتاج تھا جب ان چیزوں نے گواہی دے دی توثابت ہو گیا کہ محمد رسول اللہ صلے اللہ علیہ وآلہٖ وسلم نے جب کہا تھا کہ پہاڑ گواہی دیںگے یا دریا گواہی دیں گے تو انہوں نے یہ بات اپنی طرف نہیں کہی تھی بلکہ خد اکی طرف سے کہی تھی.پس مخلوق نے خدا تعالیٰ کو سچا ثابت نہیں کیا بلکہ اُس انسان مدعی کو سچا ثابت کیا جو خدا تعالیٰ کی طرف ایک کلام منسوب کر رہا تھا.اس سوال کا جواب کہ اگر قرآن مجید کی صداقت کے لئے حلف کی ضرورت تھی تو آنحضرت صلعم کو حلف اٹھانا چاہیے تھا نہ کہ خدا کو اگر کہا جائے کہ جب سوال صرف اُس انسان کی سچائی کا ہوتا ہے جو خدا کا کلام پیش کر رہا ہوتا ہے تو اُسے خود قسم کھانی چاہیے نہ کہ خدا تعالیٰ کو.تو اس کا جواب یہ ہے کہ اوّلؔ وہ انسان بھی الگ قسم کھایا کرتا ہے لیکن چونکہ الٰہی کلام بھی مکمل ہوتا ہے اس لئے اُس کے اندر بھی حلف کا ثبوت جو دنیا میں اکثر لوگوں کے نزدیک سب سے کامل ہوتا ہے ہونا چاہیے تا اندرونی شہادت اس امر پر موجود ہو کہ وہ کلام مکمل ہے ورنہ وہ مکمل نہیں رہے گا.اگر کلام الٰہی میں حلف موجود نہ ہو بلکہ نبی اپنے دعویٰ کی صداقت میں علیحدہ طور پر قسم کھائے تو اس کی حلف اوّل مستقل نہیں ہو گی جیسے حدیثوں میں اس قسم کی حلف کی کئی مثالیں موجود ہیں.مگر حدیثوں کے متعلق لوگ شبہ کرتے ہیں کہ نہ معلوم وہ صحیح ہیں یا نہیں.اُن کا یہ شبہ صحیح ہو یا غلط یہ الگ بحث ہے لیکن اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ لوگوں کو اس قسم کے شبہ کی گنجائش ہے اور ہم بھی دعویٰ سے نہیں کہہ سکتے کہ ہر حدیث صحیح ہے یاہر حدیث انہی الفاظ میں ہے جو رسول کریم صلے اللہ علیہ وآلہٖ وسلم نے فرمائے.یقینی اور قطعی کلام جس کے ایک ایک لفظ پر ہم حلف اٹھا کر کہہ سکتے ہیں کہ وہ خدا تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے اور اسی طرح ہے جس طرح رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم نے اسے بیان فرمایا وہ صرف قرآن کریم ہی ہے.چنانچہ میور اور نولڈک جیسے دشمنانِ اسلام بھی یہ اقرار کرنے پر مجبور ہوئے ہیں کہ قرآن کریم کا ایک ایک لفظ جس طرح محمد صلے اللہ علیہ وسلم نے بتایا اُسی طرح آج تک موجود ہے اُس میں ذرا بھی تغیّر و تبدّل نہیں ہوا(لائف آف محمد سر ولیم میورصفحہ ۵۶۲ ،۵۶۳ زیر عنوان sources for the biography of Mahomet انسائیکلوپیڈیا برٹینیکا زیر لفظ Koran).پس اگر اس کلام میں قسم موجود ہو گی تو یہ اس بات کا ایک قطعی اور یقینی ثبوت ہو گا.کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم نے قسم کھائی ہے.اگر اس کلام میں قسم موجود نہ ہوتی تو دوسری قسمیں جو حدیثوں وغیرہ میں آتی ہیں وہ اس قِسم کی قطعی اور یقینی نہیں ہو سکتی تھیں.پس الٰہی کلام میں بھی حلف کا ثبوت موجود ہونا چاہیے تھا تا کہ یہ اندرونی شہادت دوسری شہادتوں کی تکمیل کرتی.
Page 124
دوسرے کلام الٰہی میں کلام لانے والے کی حلف نہیں ہو سکتی بلکہ خدا تعالیٰ کی ہی ہو گی.اگر نبی کی حلف ہو گی تو کلام اللہ میں انسانی کلام مل جائے گا.مثلاًمحمد رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم یہ کہتے کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مجھے خدا تعالیٰ نے بھیجا ہے اور یہ الفاظ قرآن کریم میں موجود ہوتے تو اس کے معنے یہ ہوتے کہ کلام اللہ میں غیر کا کلام بھی شامل ہو گیا حالانکہ قرآن کریم وہ کتاب ہے جو بسم اللہ کی باء سے لے کر والناس کے س تک تمام کا تمام خدا تعالیٰ کا کلام ہے یا اگر محمد رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کا یہ فقرہ اُس میں موجود ہوتا کہ اے لوگو سنو میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں تو اس صورت میں بھی انسانی کلام اللہ تعالیٰ کے کلام میں شامل ہو جاتا.اور اگراللہ تعالیٰ کے کلام میں یہ آ جاتا کہ اے محمد صلے اللہ علیہ وسلم ہم تجھے کہتے ہیں کہ تواپنے دعویٰ کی صداقت کے متعلق لوگوں کے سامنے قسم کھا تب بھی شبہ کی گنجائش رہتی کہ نہ معلوم انہوں نے قسم کھائی ہے یا نہیں کھائی.جیسے قرآن کریم میں کئی مقامات پر آتا ہے کہ قُلْ یعنی اے محمد صلے اللہ علیہ وسلم تُو لوگوں سے ایساکہہ دے.اب گو ہمارا یقین ہے کہ رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام باتیں لوگوں سے کہہ دیں مگر پھر بھی لفظ قُلْ سے ایک دشمن کی نگاہ میں تو یہ ثابت نہیں ہوتا کہ محمد رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے کہہ بھی دیا تھا.اسی طرح اگر قرآن کریم میں ہوتا اے محمد صلے اللہ علیہ وسلم تُو قسم کھا تو دشمن کہہ سکتے تھے کہ کیا معلوم انہوں نے قسم کھائی تھی یا نہیں بہرحال دونوں صورتوں میں قسم کی غرض فوت ہو جاتی.اگر کلام الٰہی میں محمد رسول اللہ صلے اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کی قسم آجاتی تو کلام الٰہی میں انسانی کلام مل جاتااور اگر خدا تعالیٰ اپنے کلام میں رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم کو قسم کھانے کی ہدایت فرماتا تو پھر بھی لوگوں کو یہ شبہ رہتا کہ نہ معلوم انہوں نے اس کے مطابق قسم کھائی تھی یا نہیں اور اگر الگ قسم کھا لیتے تب بھی کلام الٰہی اس زبردست ثبوت کی عدم موجودگی کی وجہ سے نامکمل رہتا.دوسری بات یہ مدنظر رکھنی چاہیے کہ قرآ ن کریم نے جن امورپر قسم کھائی ہے یا جن امور کو اپنی صداقت کے ثبوت کے طور پر پیش کیا ہے اُن میں سے کم سے کم ایک حصہ تو ضرور ایسے علوم سے تعلق رکھتا ہے جو محمد رسول اللہ صلے اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کے علم اور قبضہ سے بالا تھے (میرے نزدیک سب قسمیں ہی ایسے امور پر مشتمل ہیں)اُن کو شہادت کے طور پر وہ پیش ہی کس طرح کر سکتے تھےانہیں تو خدا تعالیٰ جو علیم وخبیر ہے وہی پیش کر سکتا تھا اور اُسی نے پیش کیا.پس یہ سوال کہ قسم اُس انسان کی کھانی چاہیے تھی جس پر خدا کا کلام نازل ہو رہا تھا نہ کہ خدا تعالیٰ کو.بالکل غلط ہے.محمد رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کو تو ان چیزوں کا علم ہی نہیں تھا اور نہ یہ چیزیں اُن کے قبضہ اور اختیار میں تھیں پھر وہ اُن کی قسم کس طرح کھا سکتے تھے.پس قسمیں چونکہ علوم غیبیہ پر مشتمل ہوتی ہیں اس لئے کوئی نبی وہ قسمیں کھا
Page 125
ہی نہیں سکتا کیونکہ اُسے معلوم ہی نہیں ہو سکتا کہ آئندہ کیا کچھ ہونے والا ہے خدا تعالیٰ ہی ہے جو ان چیزوں کو شہادت کے طور پر پیش کر سکتا ہے.اگر کہا جائے کہ قسم کی ضرورت ہی کیا ہے بہت سے لوگ قسم کو وقعت ہی نہیں دیتے اور وہ کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی قسم کا کیا سوال ہے قسم تو بندے کو بھی نہیں کھانی چاہیے چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پادری آتھم کے مقابلہ میں یہ بات پیش کی کہ اگر پیشگوئی کی ہیبت اس کے دل پر طاری نہیں ہوئی تو وہ قسم کھا کر اعلان کر دے تو عیسائیوں نے یہی کہا کہ قسم کھانا کوئی اچھی بات نہیں ہم اس طریق فیصلہ کو قبول نہیں کر سکتے(ضیاء الحق روحانی خزائن جلد ۹ صفحہ ۲۵۶.۲۵۷).تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قسم کی کوئی قیمت ہی نہیں سمجھتے اور اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ الٰہی کلام میں بھی قسمیں نہیں آنی چاہئیں.اس سوال کا جواب یہ ہے کہ بے شک بعض لوگ قسم کو وقعت نہیں دیتے مگر کسی کے وقعت نہ دینے سے کیا بنتا ہے.سوال تو یہ ہے کہ قسم اپنی ذات میں وقعت رکھتی ہے یا نہیں؟ اگر رکھتی ہے تو بےشک بعض لوگ اُسے وقعت نہ دیں ان کی وجہ سے ایک سچائی کو چھوڑا نہیں جا سکتا اگر کوئی خدا ہے تو اُس کی جھوٹی قسم کھانا یقیناً سخت عذاب کا موجب ہونا چاہیے بشرطیکہ دنیا کو اُس سے کوئی بڑا نقصان پہنچتا ہو لغو قسم نہ ہو.پس قسم اپنی ذات میں ایک بہت بڑا ثبوت ہے اور بعض کے نہ ماننے کی وجہ سے اُسے چھوڑا نہیں جا سکتا.دوسراؔ جواب یہ ہے کہ اگر بعض اُسے مفید نہیں سمجھتے تو بعض دُوسرے اُسے ایک اہم دلیل قرار دیتے ہیں.بے شک کچھ حصّہ ایسے لوگوں کا بھی ہے جو کہتے ہیں کہ قسم ایک لغو اور فضول چیز ہے مگر کچھ حصہ ایسے لوگوں کا بھی ہے جن کی قسم کھانے کے بغیر تسلّی ہی نہیں ہوتی.جو کلام ساری دنیا کے لئے آئے گا اُس کے لئے ضروری ہو گا کہ اگر کسی ایک گروہ کا مطالبہ بھی جائز اور درست ہو تو اُس کو پورا کرے.کیونکہ قرآن کریم صرف اُن لوگوں کے لئے نہیں جو قسم کو کوئی وقعت نہیں دیتے.بلکہ ساری دنیا کے لئے ہے جن میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جن کاقسم کے بغیر اطمینان ہی نہیں ہوتا.پس جہاں جہاں قسمیں نہیں کھائی گئیں اُس حصۂ قرآن سے وہ لوگ فائدہ اُٹھا سکتے ہیں جو قسموں کو ضروری نہیں سمجھتے اور جہاں قسمیں کھائی گئی ہیں اُسی حصہ سے وہ لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو قسموں کو ضروری سمجھتے ہیں.اگر صرف ایک گروہ کا مطالبہ پورا کر دیا جاتا اور دوسرے گروہ کا جائز مطالبہ ردّ کر دیا جاتا تو قرآن کریم سب لوگوں کے لئے نہیں ہو سکتا تھا.پھر وہ ایک محدودطبقہ کے لئے رہ جاتا.غرض چونکہ دنیا میں ایک ایسا گروہ بھی موجود ہے جو قسموں پر اعتبار کرتا ہے بلکہ اسے ضروری سمجھتا ہے اس لئے قرآن کریم کا فرض تھا کہ وہ اور دلائل کے ساتھ اس دلیل کو بھی پیش کر دیتا اور اُس ثبوت کو ترک نہ کرتا جو ایک طبقہ کے اطمینان کے لئے ضروری تھا.حدیثوں میں آتا ہے رسول کریم
Page 126
صلے اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کے پاس ایک دفعہ ایک شخص آیا اور اُس نے کہا میں آپ سے یہ بات دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ آپ خدا کی قسم کھا کر کہہ سکتے ہیں کہ آپ جو باتیں کہہ رہے ہیں اُن کے کہنے کا آپ کو خدا نے حکم دیا ہے؟ رسول کریم صلے اللہ علیہ وآلہٖ وسلم نے فرمایا مَیں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہہ رہا ہوں.اِس پر وہ اسی وقت آپ پر ایمان لے آیا (صحیح بخاری کتاب العلم باب ما جاء فی العلم و قولہ تعالیٰ و قل رب زدنی علما.صحیح مسلم کتاب الایمان باب السوال عن ارکان الاسلام) گویا اور دلیلوں سے تو اُس کو تسلی نہ ہوئی لیکن جب رسول کریم صلے اللہ علیہ وآلہٖ وسلم نے قسم کھا لی تو اس کی تسلّی ہو گئی.قرآن مجید میں ہر قسم کے لوگوں کے لئےدلائل تو جب ایک گروہ دنیا میں ایسا ہے جس کی قسم سے ہی تسلی ہو سکتی ہے تو اگر اللہ تعالیٰ کے کلام میں قسم موجود نہ ہوتی تو ایسا گروہ صداقت کے قبول کرنے سے محروم رہ جاتا اور کلام الٰہی پر یہ اعتراض عائد ہوتا کہ وہ دعویٰ تو یہ کر رہا ہے کہ تمام لوگوں کی ہدایت اور راہنمائی کے لئے نازل ہوا مگر ایک طبقہ کے جائز مطالبہ کو اس میں نظر انداز کر دیا گیا ہے.حضرت مسیح موعودعلیہ السلام کا اپنی صداقت کے لئے قسم کھانا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانہ میں بھی بعض ایسے واقعات ہوئے ہیں.ایک دفعہ آپ کے پاس ایک شخص آیا اور آکر کہنے لگا کیا آپ قسم کھا کر مجھے لکھ کر دے سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسیح موعود بنایا ہے؟ آپ نے فرمایا ایک ہفتہ کے بعد آنا.جب وہ ہفتہ کے بعد آیا تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اُسے ایک تحریر لکھ کر دی جس کا مضمون یہ تھا کہ میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے جو کچھ اپنی کتابوں میں لکھا ہے یا اپنی تقریروں وغیرہ میں بیان کرتا ہوں یہ تمام علوم مجھے خدا نے عطا فرمائے ہیں اور خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ان باتوں کو لوگوں کے سامنے پیش کروں اور اُسی کے حکم سے میں نے مسیح موعود اورمہدی موعود ہونے کا دعویٰ کیا ہے(ایک ہفتہ بعدآنے کی شرط غالباً آپ نےاس لئے لگائی تا اس شخص کی سنجیدگی کا ثبوت مل جائے.ورنہ بعض لوگ تماشہ کے طور پر سوال کر دیتے ہیں آپ نے ایک ہفتہ کے بعد آنے کی شرط لگا کر امتحان کر لیا کہ وُہ شخص سنجیدہ ہے اور وقت مقررہ پر پھر تکلیف اٹھا کر آیا ہے جب یہ امتحان ہو گیا تو آپ نے قسم تحریر فرما دی) تو ایک طبقہ ایسا ہوتا ہے جو اور کسی دلیل کا متلاشی نہیں ہوتا.وہ کہتا ہے اگر یہ بات سچ ہے تو پھر اس پر قسم کھا جائو.اس قسم کی فطرت والوں کی اصلاح اور ہدایت کے لئے ضروری تھا کہ قرآن کریم میں قسمیں ہوتیں تا کہ یہ گروہ قبولِ ہدایت سے محروم نہ رہ جاتا.
Page 127
تیسرے قرآن کریم کی قسمیں خود اپنی ذات میں ایک ثبوت ہیں چنانچہ قرآن کریم میں جہاں جہاں قسمیں کھائی گئی ہیں اللہ تعالیٰ نے اُن چیزوں کو شہادت کے طور پر پیش کیا ہے اور فرمایا ہے کہ اگر یہ چیزیں شہادت دے دیں تو ثابت ہو جائے گا کہ یہ کلام خدا تعالیٰ کا ہی تھا.اور اگر شہادت نہ دیں تو بیشک اس کے الٹ نتیجہ نکالنا.پس وہ قسمیں خود اپنی ذات میں قرآن کریم کی سچائی کا ایک بہت بڑا ثبوت ہیں.اُن کا نام حلف رکھو یا شہادت بات ایک ہی ہے بلکہ اگر وہ شہادتِ محضہ کے رنگ میں بھی بیان ہوں تب بھی قرآن کریم کی صداقت کا ایک ثبوت ہیں پس جو لوگ حلف کو وقعت نہیں دیتے وُہ اُن کو شہادت سمجھ کر فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور جو حلف کو وقعت دیتے ہیں وہ اسے شہادت مؤکد بہ حلف سمجھ کر فائدہ اٹھا سکتے ہیں گویا ایک ہی وقت میں دو مختلف طبائع کے لوگوں کی تسلی کا وہ موجب ہو سکتی ہیں اور اس لئے وہ قابلِ قدر شئے ہیں نہ کہ قابل اعتراض.کیونکہ ان قسموں نے دونوں قسم کی ضرورتوں کو پورا کر دیا.(قرآنی قسموں کے متعلق ایک مکمل مگر اجمالی بحث انشاء اللہ پہلی قسم کے ماتحت لکھی جائے گی اور تفصیلی بحث تو ہر قسم کے نیچے آ جائے گی.امام ابن قیم کی اقسام القرآن کتاب بھی اس بارہ میں مطالعہ کے قابل ہے اور بہت سی مفید باتیں اُس میں بیا ن ہوئی ہیں.جزاہ اللّٰہ خیراً عن المسلمین) جن چیزوں کی اس آیت اور اگلی آیتوں میں قسم کھائی گئی ہے وہ کیا ہیں.اس کی مفصل بحث فَالْمُدَبِّرٰتِ۠ اَمْرًا کی آیت کے آخر میں آئے گی.وَّ النّٰشِطٰتِ نَشْطًاۙ۰۰۳ اور اُن (ہستیوں) کی جو گرہ باندھتی ہیں خوب اچھی طرح.حلّ لُغَات.نَاشِطَات نَاشِطَات نَشَطَ سے اسم فاعل کا جمع مؤنث کا صیغہ ہے.اور نَشِطَ یَنْشَطُ نَشَاطًا کے معنے ہوتے ہیں طَابَتْ نَفْسُہٗ لِلْعَمَلِ اُس نے کام کےمتعلق اپنے اندر رغبت اور خوشی پیدا کی.اور نَشَطَ( یَنْشُطُ نَشَطًا) الْحَبْلَ کے معنے ہوتے ہیں عَقَدَہٗ رسّے کو اُس نے گرہ دی.اور نَشَطَ الْعُقْدَۃَ کے معنے ہوتے ہیں اشَدَّھَا گرہ کو اس نے سخت باندھا اور جب کہیں نَشَطَ الدَّلْوَمِنَ الْبِئْرِ تو اس کے معنے ہوتے ہیں نَزَعَھَا بِغَیْرِ قَامَۃٍ وَاِنْتَشَلَھَا بِلَا بَکْرَۃٍ اُس نے ڈول کو بغیر چرخی کے ہاتھوں سے کھینچا.اور جب یہ لفظ ان معنوں میں استعارۃً استعمال ہو گا تو اس کا مطلب یہ ہو گا کہ اُس نے بہت زور لگا یا کیونکہ جب پانی بغیر چرخی کے نکالا
Page 128
جائے تو بہت زور لگتا ہے.اِسی طرح کہتے ہیں نَشَطَ زَیْدًاا ور اس کے معنے ہوتے ہیں طَعَنَہٗ اُس کو نیزہ مارا.اور جب کہیں نَشَتَطْہُ الْحَیَّۃُ تو اس کے معنے ہوتے ہیں عَضَّتْہُ اُس کو سانپ نے کاٹ لیا(اقرب) اور نَشَطَتِ الْاِبِلُ کے معنے ہوتے ہیں مَضَتْ عَلٰی ھُدًی اَوْغَیْرِ ھُدًی اونٹ کسی خاص راستہ پر یا یونہی جنگل میں اِدھر اُدھر چل پڑا (اقرب) پس نَاشِطَات کے معنے ہوں گے (ا)ایک چیز کو دوسری سے باندھنے والی ہستیاں (۲)کام کو کرتے وقت بہت زور لگانے والے گروہ (۳)نیزہ زنی کرنےوالے گروہ.تفسیر.اس آیت کی تشریح فَالْمُدَبِّرٰتِ۠ اَمْرًا کی آیت کے بعد آئے گی.وَّ السّٰبِحٰتِ سَبْحًاۙ۰۰۴ اور اُن (ہستیوں) کی جو دُور دُور نکل جاتی ہیں.حلّ لُغَات.اَلسَّابِحَاتِ السَّابِحَات سَبَحَ سے اسم فاعل کا جمع مؤنث کا صیغہ ہے.ا ور جب سَبَحَ الرَّجُلُ کا فقرہ کہیں تو اس کے معنے ہوتے ہیں تَصَرَّفَ فِیْ مَعَاشِہٖ انسان اپنے معاش کے کاموں میں لگ گیا اسی طرح اس کے معنے ہوتے ہیں نَامَ ؔ.سو گیا.سَکَنَؔ.ٹھہر گیا.اَبْعَدَ فِیْ السَّیْرِ.دور نکل گیا.اور سَبَحَ فِیْ الْکَلَامِ کے معنے ہوتے ہیں اَکْثَرَ فِیْہِ.اُس نے لمبی گفتگو کی اور سَبَحَ فِی الْاَرْضِ کے معنے ہوتے ہیں حَفَرَ فِیْھَا.اُس نے زمین میں گڑھا کھودا.اور سَبَحَ فِیْ النَّھْرِ وَبِالنَّھْرِ کے معنے ہوتے ہیں عَامَ وَانْبَسَطَ فِیْہِ پانی میں تیراا ور تیرتے تیرتے دُور نکل گیا.اور سَبَحَ سُبْحَانًا کے معنے ہوتے ہیں قَالَ سُبْحَانَ اللّٰہِ.اُس نے سبحان اللہ کہا (اقرب) پس اَلسَّابِحَات کے ایک معنے ہوں گے.وہ گروہ جو دُور دُور نکل جاتے ہیں (۲)وہ گروہ جو قادرالکلام ہیں.(۳)وہ گروہ جو خوب تیرنے والے ہیں (۴) وہ گروہ جو اپنے معاش کو خود پیدا کرتے ہیں.تفسیر.اس آیت کی تشریح فَالْمُدَبِّرٰتِ۠ اَمْرًا کی آیت کے بعد آئے گی.فَالسّٰبِقٰتِ سَبْقًاۙ۰۰۵ پھر (مقابلہ کر کے اپنے مد مقابل سے) خوب آگے نکل جاتی ہیں.حلّ لُغَات.اَلسَّابِقَات السَّابِقَات سَبَقَ سے اسم فاعل کا جمع مؤنث کاصیغہ ہے اور سَبَقَ
Page 129
(یَسْبِقُ) سَبْقًا کے معنے ہوتے ہیں تَقَدَّمَہٗ وَجَازَہُ وَخَلَّفَہٗ کسی کے آگے نکل گیااور اس کو پیچھے چھوڑ گیا.اور سَبَقَ عَلَی الشَّیْئِکے معنے ہوتے ہیں غَلَبَہٗ اس پر غالب آگیا.(اقرب) پس اَلسَّابِقَات کے معنے ہوں گے.وہ گروہ جو دوسروں سے آگے نکل جاتے ہیں.(۶) وہ ہستیاں جو دوسروں پر غالب آجاتی ہیں.تفسیر.اس آیت کی تشریح اگلی آیت کے بعد آئے گی.فَالْمُدَبِّرٰتِ۠ اَمْرًاۘ۰۰۶ پھر جو (دنیا کا) کام (چلانے) کی تدبیروں میں لگ جاتی ہیں.حلّ لُغَات.المُدَبِّرَات تَدْبِیْر کے معنے آگے پیچھے کرنے کے ہوتے ہیں چنانچہ کہتے ہیں دَبَّرَالْاَمْرَ اَیْ رَتَّبَہٗ وَنَظَّمَہٗ کسی چیز کے کسی حصہ کو پہلے رکھا اور کسی کو بعدمیں رکھا اور اس طرح اس کی ترتیب دی.نیز کہتے ہیں دَبَّرَ الْاَمْرَ اَیْ نَظَرَ فِیْ عَاقِبَتِہٖ وَتَفَکَّرَ کسی امر کے تمام پہلوئوں پر غور کر کے اس کا انتظام کیا اور جب دَبَّرَ الْوَالِیْ اَقْطَاعَہٗ کہیں تو معنے ہوتے ہیں اَحْسَنَ سِیَاسَتَہٗ یعنی منتظم نے اپنی جاگیر کا اچھا انتظام کیا (اقرب) مُدَبِّرَات اسم فاعل کا جمع مؤنث کا صیغہ ہے پس فَالْمُدَبِّرٰتِ اَمْرًا کے معنے ہوں گے کسی بات کے تمام پہلوئوں کو دیکھ کر معاملہ کا انتظام کرنےوالے گروہ.گویا مدبّر کے لفظ میں منتظم کا فرض بھی بیان کر دیا گیا ہے کہ وہ تمام پہلوئوں کو دیکھ کر انتظام کرتا ہے.یہ نہیں ہوتا کہ وہ ایک بات کوتو دیکھے اور دوسری باتوں کو نظر انداز کر دے.تفسیر.سورۃ نازعات کی پہلی پانچ آیتوں کی تفسیر مختلف مفسرین کے نزدیک ان آیات کے متعلق اپنا نقطہ نظر پیش کرنے سے پہلے میں مفسّرین کے مختلف اقوال کو پیش کرتا ہوں اسی میں یہ بھی ذکر آجائے گا کہ ہمارے پُرانے بزرگوں نے اِن آیات کے کیا معنے کئے ہیں.پہلے میں وَ النّٰزِعٰتِ غَرْقًا اور وَ النّٰشِطٰتِ نَشْطًا کو لے لیتا ہوں نازِعَات اور نَاشِطَات کے متعلق اکثر مفسّرین اور صحابہ ؓ اور اُمتِ محمدؐیہ کے بزرگوں کے جو اقوال ملتے ہیںوہ خلاصۃً یہ ہیں.صاحبِ کشّاف لکھتے ہیں نَازِعَات اور نَاشِطَات فرشتوں کے وہ گروہ ہیں جو جسم کی گہرائیوں میں جا کر جان نکالتے ہیں اور پھر اُسے باہر نکالتے ہیں (جو نَشْطًا کے معنے ہیں) اور پھر اُس گروہ کی قسم کھائی جو خدا تعالیٰ کے احکام کے پورا کرنے میں تیزی سے کام کرتا ہے اور اس کے حکم کے ماتحت امورِ عالم کی تدبیر کرتا ہے.(کشاف زیر آیت ھذا) فتح البیان میں اُوپر کے معنوں کو بیان کرنے کے بعد لکھا ہے کہ یہ قول اکثرصحابہؓ اور تابعین اور اُن کے بعد
Page 130
کے لوگوں کا ہے.پھر لکھا ہے سدیؔ کہتے ہیں کہ نَازِعَات سے مراد نفوس ہیں جب وہ سینہ میں غرق ہو جاتے ہیں یعنی موت کے وقت.اور مجاہد کہتے ہیں کہ نَازِعَات سے مراد موتیں ہیں جو روحوں کو نکالتی ہیں اور قتادہ کہتے ہیں کہ ان سے مراد ستارے ہیں جو ایک افق سے دوسرے افق کی طرف جاتے ہیں اور پھر دوسرے افق سے نکل آتے ہیں اور ابو عبیدہ ؔ اور اخفشؔ اور ابن کَیْسَان کا بھی یہی قول ہے.اور اس حد تک یہ معنے درست ہیں کہ لغت میں لکھا ہے نَزَعَ اِلَی الشَّیْئِ نَزَاعًا: ذَھَبَ اِلَیْہِ یُقَالُ ’’ لَہٗ نَزْعَۃٌ اِلٰی کَذَا‘‘ یعنی نَزَعَ اِلَی الشَّیْئِ کے معنے ہوتے ہیں.وہ اس طرف جاتا ہے اِسی طرح کہتے ہیں نَزَعَ بِفُلَانٍ اِلٰی کَذَا: دَعَاہُ اِلَیْہِ یعنی اس شخص کو فلاں کام کی طرف بلایا (اقرب) اور نَزَعْتُ بِالْحَبْلِ کے معنے ہوتے ہیں میں نے رسّہ سےکھینچا.گویا لغت کے لحاظ سے ایک طرف سے جانااور دوسری طرف سے نکل آنا اس کا مفہوم ہوتا ہے.چونکہ ستارے بھی ایک طرف سے جاکر دوسری طرف سے نکل آتے ہیں اس لئے انہیں نَازِعَاتِ غَرْقًا کہا گیا.عطاءؔ اور عکرمہؔ کا قول ہے کہ نَازِعَات کمانیں ہیں کہ تیر پھینکتی ہیں اور غَرْقًا سے مراد اِغْرَاقٌ ہے کہ تیر انداز تیر کو اس قدر کھینچتا ہے کہ تاند کے ساتھ تیر کا نوک آ لگتا ہے.اور بعض نے کہا ہے کہ نَازِعَات سے مراد وہ غازی ہیں جو تیر اندازی کرتے ہیں.گویا اُ ن کے نزدیک غَرْقًا پر نصب بطور مصدر ہے اور مراد اِغْرَاقًا ہے چنانچہ کہتے ہیں اَغْرَق فِیْہِ: (یُغْرِقُ) اِذَابَالَغَ غَایَتَہٗ یعنی کام کو اس کی انتہائی حد تک پہنچایا.(فتح البیان زیر آیت ھذا) اور مراد یہ ہے کہ وَالنَازِعَاتِ وَالْمُغْرِقَات غَرْقًایا اِغْرَاقًا ہم شہادت کے طور پر پیش کرتے ہیں تیروں کو کھینچنے والے نفوس کو جو اتنا کھینچتے ہیں کہ تیر کا اگلا سرا کھنچ کر تاند تک آجاتا ہے.حضرت علیؓ کا قول ہے کہ یہ ارواح کفّار ہیں.(فتح البیان ) حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ کفّار کی ارواح پہلے کھینچی جاتی ہیں پھر نکالی جاتی ہیں پھر آگ میں پھینک دی جاتی ہیں.سابق مفسرین کے نزدیک وَ النّٰشِطٰتِ نَشْطًا کا مطلب وَ النّٰشِطٰتِ نَشْطًا.ابن عباس اور سدیؔ کہتے ہیں کہ اس سے مراد نفوس ہیں جو قدموں سے نکالے جاتے ہیں.گویا جان تمام جسم میں پھیلی ہوئی ہوتی ہے لیکن جب قدموں کے پاس سے نکالی جائے تو اُن جانوں کو نَاشِطَات کہتے ہیں.مجاہد کہتے ہیں اس سے مراد موت ہے جو نفوس انسانی کو نکالتی ہے قتادہؔ.حسنؔ اور اخفشؔ کہتے ہیں کہ ستارے ہیں کہ ایک افق سے دوسرے افق کی طرف جاتے ہیں.صاحب الصحاح کہتے ہیں کہ ستا رے ہیں جو ایک برج سے دوسرے برج کی طرف جاتے ہیں.بعض کہتے ہیں کہ نَاشِطَات کا لفظ رواحِ مومنین کی طرف اشارہ کرتا ہے اور نَازِعَات سے ارواحِ کفّار کی طرف اشارہ ہے مگر حضرت علیؓ ناشطات کو کفار کی ارواح نکالنے کی طرف اشارہ بتاتے ہیں اسی کے مطابق معاذؔابن جبلؓ سے
Page 131
ابن مردو یہ نے ایک حدیث بھی نقل کی ہے کہ نَاشِطَات دوزخ کے کُتّے ہیں جو گوشت نوچیں گے جس کا مطلب یہ نکلا کہ نَاشِطَات میں مومنوں کی روح کا ذکر نہیں بلکہ کفّار کا ذکر ہے کیونکہ دوزخ کے کتے تو کفار پر ہی حملہ آور ہوں گے.(فتح البیان) مفسرین کے نزدیک سابحات کے معنے وَ السّٰبِحٰتِ سَبْحًا بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد ملائکہ ہیں جو مومنوں کی جان نرمی سے نکالتے ہیں.مجاہدؔ اور ابو صالحؔ کا قول ہے کہ اس سے ملائکہ مراد ہیں جو آسمان سے خدا تعالیٰ کا حکم پورا کرنے کے لئے دوڑتے ہوئے اُترتے ہیں.مجاہد کا یہ قول بھی ہے کہ اس سے مرادموت ہے جوجسموں میں تیرتی ہے.بعض نے کہا ہے کہ یہ گھوڑے ہیں جو غزوات میں دوڑتے ہیں.قتادہؔ اور حسنؔ کہتے ہیں کہ یہ ستارے ہیں جو افلاک میں پھرتے ہیں جیسے فرمایا کُلٌّ فِیْ فَلَکٍ یَّسْبَحُوْنَ (الانبیاء :۳۴) عطاء کہتے ہیں کہ کشتیاں ہیں کہ پانی میں تیرتی ہیں بعض نے کہا ہے کہ مومنوں کی ارواح ہیں کہ لقاء الٰہی کے شوق میں تیرتی ہیں.حضرت علیؓ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا یہ ملائکہ ہیں جو مومنوںکی ارواح کو لے کر آسمان میں دوڑتے ہیں.(فتح البیان) سَابِقَاتِ سَبْقًاکے متعلق مفسرین کی رائے فَالسّٰبِقٰتِ سَبْقًا مجاہدؔ اور مسروقؔ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ملائکہ ہیں کہ وحی لے کر شیطانوں سے آگے پہنچتے ہیں اورابوروقؔ کہتے ہیں کہ ملائکہ ہیں کہ انسانوں سے عمل اور خیر میں آگے نکل گئے.مجاہدؔ کا بھی ایسا ہی قول ہے اور مقاتلؔ کہتے ہیں کہ ملائکہ ہیں جو ارواحِ مومنین کو لے کر آگے نکل جاتے ہیں.ربیعؔ کا قول ہے کہ ارواحِ مومنین ہیں کہ لقاء الٰہی کے شوق میں ملائکہ کی طرح دوڑتی ہیں.حضرت علی ؓ کہتے ہیں کہ ملائکہ ہیں کہ مومنوں کی ارواح لے کر ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں.مجاہد کہتے ہیں کہ اس سے مراد موت ہے کہ انسان کو دوڑ کرجا پکڑتی ہے.قتادہ اورحسن اور معمر کہتے ہیں کہ ستارے ہیں کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں.(فتح البیان زیر آیت والنازعات غرقا والناشطات نشطا) (یہاں ضمنی طور پر میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ بات قرآن کریم کے خلاف ہے کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رات اور دن کا آنا جانا ہمارے ایک قانون کے مطابق ہو رہا ہے اور تمام سیّارے اور ستارے اسی قانون کے ماتحت گردش کر رہے ہیں.وہ ایک دوسرے سے سباق کی کوشش نہیں کر سکتے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَاالشَّمْسُ یَنْبَغِیْ لَھَآ اَنْ تُدْرِکَ الْقَمَرَ وَلَاَالَّیْلُ سَابِقُ النَّھَارِ(یٰس:۴۱) کہ نہ سورج چاند کو پکڑ سکتا ہے اور نہ رات دن سے بڑھ سکتی ہے پس قرآن کریم کی یہ آیات قتادہ اور حسن اور معمر کی متذکرہ بالا بات کو ردّ کرتی ہیںکہ ستارے ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں)
Page 132
عطاء کہتے ہیں کہ اس سے مراد گھوڑے ہیں کہ جہاد میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں.اس جگہ پر جُرجانی کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ پہلے تو ان آیات میں وائو وائو آئی تھی مگر یہاں فاء آگیاہے پس سَابِقَات پرجو عطف آیا ہے یہ دلیل ہے اس بات کی کہ سَابِحَات سَابِقَات کا سبب ہے اور سَابِقَات نتیجہ ہے جو سَابِحَات کے بعد بیان کیا گیا ہے یعنی بوجہ تیرنے کے آگے نکل جاتے ہیں.مگر واحدیؔ کہتے ہیں یہ دلیل باطل ہے اس لئے کہ آگے مُدَبِّرَات پر بھی فاء ہے اور آگے نکل جانا کسی کام کی تدبیر کرنے کا سبب نہیں ہو سکتا یعنی اگر وائو کی جگہ فَالسَّابِقَات پر فاء آنے کے سبب سے سَابِحَات کو سَابِقَات کا سبب قرار دیا جائے تو ماننا پڑے گا کہ چونکہ مُدَبِّرَات سے پہلے بھی فاء آیا ہے اس لئے تدبیر کا سبب آگے نکل جانا ہے مگر یہ درست نہیں کیونکہ آگے نکل جانے کا فعل تدبیر کرنے کا سبب نہیں بن سکتا.پس مُدَبِّرَات کے لفظ سے پہلے بھی فاء کا آنا بتاتا ہے کہ یہ دلیل غلط ہے.امام رازی کہتے ہیں کہ واحدی کا یہ اعتراض درست نہیں کیونکہ سَبْحٌ اورپھر سِبَاقٌ اور پھر تَدْبِیْر امر فی الواقعہ ایک دوسرے سے وابستہ ہیں اور اسی وجہ سے ایک ترتیب میں سب کا ذکر آتا ہے اس پر مؤلف فتح البیان کہتے ہیں کہ اتّصال اور سبب میں فرق ہے اس لئے رازی کا یہ جواب غلط ہے.فاء محض عطف کے لئے بھی آتی ہے (فتح البیان) اس لئے اس سے کسی نکتہ کے نکالنے کی ضرورت نہیں.میں نے یہ مضمون اس لئے نقل کر دیا ہے کہ بعض لوگ فاء کے استعمال سے لازمًا سبب کے معنے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تا کہ ان کے لئے یہ بحث ہدایت کا موجب ہو مگر یہ کہنا کہ فاء یونہی لایا گیا ہے یہ بھی درست نہیں اس جگہ وائو استعمال کرتے ہوئے فاء کا لانا بتاتا ہے کہ مضمون بدل گیا ہے ورنہ جب پہلی دو آیتوں پر وائو عطف لایا گیا تھا تو کیوں آخری دو آیتوں پر وائو عطف نہ لایا گیا (پہلی آیت پر جو وائو ہے وہ وائو قسم ہے) اصل بات یہ ہے کہ اس جگہ فاء ضرور دوسرے معنے دیتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ وائو کو ترک کر کے فاء کواستعمال کیا گیا ہے.اگر دوسرے معنے پیدا کرنے مقصود نہ ہوتے تو وائو عطف کا استعمال جاری رکھا جاتا.وہ دوسرے معنے کیا ہیں ؟ وہ معنے میرے نزدیک ترتیب کے ہیں ان دو آیتوں میں ضرور ایسے معنے بھی پائے جاتے ہیں جو ترتیب پر دلالت کرتے ہیں اور جو پہلی آیتوں کے مضمون کےثابت ہونے کے بعد ہی حاصل ہو سکتے ہیں چنانچہ ان معنوں کا ذکر آگے چل کر آئے گا.فَالْمُدَبِّرٰتِ۠ اَمْرًا حضرت علیؓ فرماتے ہیں اس سے مراد ملائکہ ہیں جو امر عبادت کی تدبیر سال کے شروع سے لے کر آخر تک کرتے ہیں.ابن عباسؓ کہتے ہیں ملائکہ ہیں جو ملک الموت کے ساتھ آتے ہیں کوئی رُوح اُوپر لے جاتا ہے.کوئی دعا پر آمین کہتا ہے کوئی استغفار کرتا ہے.قشیریؔ کہتے ہیں کہ اس پر اجماع ہے کہ یہاں ملائکہ کا ذکر ہے
Page 133
مگر ماوردیؔ کہتے ہیں کہ نہیں دو تفسیریں ہیں بعض نے ملائکہ مراد لئے ہیں اور بعض نے سات ستارے قرار دئے ہیں اور تدبیر امر سے بھی دو امر مراد لئے گئے ہیں ایک اُن کی حرکات کی تدبیراور دوسرے امور قضاء کی تدبیر جوان کے بارہ میں ہوں.تدبیرِ ملائکہ سے بعض نے یہ مراد لیا ہے کہ الٰہی احکام کی تنفیذ جو ملائکہ پر نازل ہوتے ہیں اس کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے.(فتح البیان) سورۃ نازعات کی پہلی پانچ آیات کی تفسیر میں مفسرین کو ایک ٹھوکر یہ قرآن کریم کے اِن پانچ جملوں کی اس تفسیر کاخلاصہ ہے جو گزشتہ مفسّرین نے کی ہے.جہاں تک اِن الفاظ کے معنوں کا سوال ہے ہمیں کسی ایسے معنے پر اعتراض نہیں ہو سکتا جو لغتاً صحیح ہوں جو معنے لغتًا جائز اور درست ہیں اُن میں سے ہر معنے اپنی اپنی جگہ پر چسپاں ہو سکتے ہیں مگر جب کسی کلام کی تفسیر کی جاتی ہے تو اس کلام کی صحیح تفیسر اور تشریح کرنے کے لئے یہ ضروری ہوتا ہے کہ دیکھا جائے کلام کا قرینہ کیا تھا یا اس کلام کا محل کیا تھا.اگر اس کلام کا محل ہم سمجھ لیں تو سب سے پہلے اس کے محل کو دیکھیں گے اور اگر محل نہ ملے تو قرینہ سے اس کلام کی تشریح کی جائے گی.مثلاً ایک شخص کہتا ہے دوڑ کر بازار سے سودا خرید لائو اور ہم بھی اُس کے اس فقرہ کو سُن لیتے ہیں تو اگراُس وقت اس کا نوکر موجود تھا تو چونکہ کلام کے محل کا ہمیں علم ہو گیا ا س لئے ہم کہیں گے کہ اُس نے اس فقرہ کے ذریعہ اپنے نوکر سے کہا تھا کہ جائو اوردوڑ کر بازار سے سودا لے آئو لیکن اگر ہم کلام کے اس محل کو تونہ دیکھیں اور یہ فقرہ سُن کر کہ دوڑ جائو یہ نتائج اخذ کرنا شروع کر دیں کہ اس سے نو کر کہاں مراد ہو سکتا ہے اِس سے تو ہر انسان مراد ہے کیونکہ ہر انسان آخر دوڑ سکتا ہے یا یہ کہنا شروع کر دیں کہ اس سے مراد فلاں بادشاہ ہو گا اور جب اس سے پوچھا جائے کہ اس کا ثبوت کیا ہے تو وہ کہہ دے کہ کیا بادشاہ دوڑ نہیں سکتا یا بادشاہ بازار سے سودا خرید کر نہیں لا سکتا یا یہ کہنا شروع کر دیں کہ اُس کے اِ س فقرہ کا مطلب یہ تھا کہ فلاں مشہور فلاسفر دوڑ کر جائے اور سودا خرید لائے یا فلاں کروڑ پتی دوڑ کر جائے اورسودا خرید لائے تو ہر شخص ہمیں پاگل اور احمق قرار دے گا اور کہے گا کہ تم موقع اور محل کو بھی تودیکھو اور یہ بھی تو سوچو کہ اُس نے جس وقت یہ بات کہی ہےاس کا نوکر سامنے کھڑا تھا بے شک بادشاہ بھی دوڑ سکتا ہے.فلاسفر بھی دوڑ سکتا ہے کروڑ پتی بھی دوڑ سکتا ہے.مگر سوال یہ ہے کہ جب اُس نے یہ بات کہی تو اس کے کلام کا محل کیاتھا.اگر ہم محل کو تو نہ دیکھیں اگر ہم اس امر کوتو نظر انداز کر دیں کہ اُس کا نوکر اس کے سامنے کھڑا تھا اور وہ اُسے مخاطب کر کے کہہ رہا تھا کہ جائو اور بازار سے سودا خرید لائواور خود ہی قیاس آرائی شروع کر دیں کہ یہ فقرہ کس کے متعلق ہے ایک کہے بادشاہ کے متعلق ہے.دوسرا کہے میرا خیال ہے کہ فلاں فلاسفر کے متعلق ہے.تیسرا کہے میرا قیاس اس طرف جاتا ہے کہ یہ فلاں کروڑ پتی کے متعلق ہے تو سب لوگ ہنسیں
Page 134
گے اور کہیں گے کہ تم کو کیا ہو گیا ہے کہ اتنی بات بھی نہیں سوچتے کہ یہ فقرہ کہاکس کو گیا تھا.بے شک بادشاہ بھی دوڑ سکتا ہے اور سودا خرید کر لا سکتا ہے.بے شک ایک فلاسفر بھی دوڑ سکتا ہے او رسودا خرید کر لاسکتا ہے.بے شک ایک کروڑ پتی بھی دوڑ سکتا ہے اور سودا خرید کر لا سکتا ہے مگر سوال تو یہ ہے کہ اس بات کا محل کیا تھا؟نوکر اس کے سامنے کھڑا تھا اور وُہ اسے کہہ رہا تھا کہ دوڑ کر بازار سے سودا خرید لائو.پس لازمًا اس سے مراد اُس کا نوکر ہی ہو گا کوئی اور شخص نہیں ہو گا پس کسی کلام کا مفہوم سمجھنے کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اُس کلام کے محل کو دیکھا جائے اور پھر اُس کلام کے کوئی معنے کئے جائیں.محل کو نہ دیکھنا اور یونہی قیاس آرائی شروع کر دینا دانائی نہیں ہوتی.دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی بات کا محل ہمیں معلوم نہ ہو سکے تو قرینہ دیکھنا چاہیے.مثلاً ایک شخص گھر میں آتا ہے نوکر اُس کے سامنے نہیں مگر وہ یہی سمجھتا ہے کہ نوکر گھر پر ہو گا.اُس وقت اتفاقًا اُسے کوئی ضروری کام پیش آجاتاہے اور وہ کہتا ہے جلّدی دوڑواور فلاں کام کر آئو.اب بیشک نوکر ہمارے سامنے نہیں ہو گا مگر یہ قرینہ تو ہو گا کہ آقا نے اپنے گھر میں یہ فقرہ کہاپس لازمًا اس سے مراد اس کا نوکر ہی ہو گا لیکن اگر قرینہ کو نہ دیکھا جائے اور یہ فقرہ لے کر ایک شخص کہے کہ دوڑ جائو جو کہا گیا ہے تو یہ فلاں دکاندار سے کہا گیا ہے.دوسر اکہے یہ بالکل غلط ہے میرا خیال ہے کہ فلاں کونہیں فلاں سے کہا گیا ہے.تیسرا کہے کہ میرا قیاس کچھ اور کہتا ہے میرے نزدیک تو فلاں سے کہا گیا ہے کہ دوڑ جائو.تو یہ ساری باتیں لغو اور بےہودہ ہوں گی.ہم کہیں گے کہ پہلے قرینہ کو بھی تو دیکھو کہ وہ کس امر کی طرف راہنمائی کرتا ہے.قرینہ بتا رہا ہے کہ ایک شخـص نے یہ بات اپنے گھر میں کہی.پس پہلاقیاس یہ ہو سکتا ہے کہ اُس نے یہ بات اپنے نوکر سے کہی ہو دوسرا قیاس یہ ہو سکتا ہے کہ اس نے یہ بات اپنےبیٹے سے کہی ہو کیونکہ بیٹا بھی خادم کی حیثیت رکھتا ہے یا اگر اُس نے بیٹے کو نہیں کہا تو ممکن ہے اُس نے اپنے کسی اور عزیز رشتہ دار کو یہ بات کہہ دی ہو مثلاً بھتیجے کو یہ بات کہہ دی ہو یا بھانجے کو یہ بات کہہ دی ہو لیکن اگر ہم قرینہ کو تو نہیں دیکھتے اور ایک فقرہ کو لے کریہ کہنا شروع کردیتے ہیں کہ اس سے فلاں مراد ہو گا یا فلاں مراد ہو گا یا فلاں اس سے مراد ہو گا تو یہ بات ہماری معقول نہ کہلا سکے گی.اِسی طرح یہاں محض یہ سوال نہیں کہ نَازِعَات کے کیا معنے ہیں یہ سوال نہیں کہ نَاشِطَات کے لغت میں کیا معنے ہیں.یہ سوال نہیں کہ سَابِحَات کے کیا معنے ہیں.یہ سوال نہیں کہ سَابِقَات کے کیا معنے ہیں.یہ سوال نہیںکہ مُدَبِّرَات کے کیا معنے ہیں بلکہ سوال یہ ہے کہ اس مقام پر اور اس جگہ پر ان الفاظ کے موقع ومحل اور قرائن کے اعتبار سے کون سے معنے ہو سکتے ہیں.پس ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس جگہ پر وہ معنے چسپاں ہو سکتے ہیں جو مفسّرین نے لئے ہیں.ـاس غرض کے لئے اوّلؔ ہم ترتیب الفاظ کو دیکھیں گے کہ آیا ترتیب الفاظ کے لحاظ سے وہ معنی
Page 135
چسپاں ہو سکتے ہیں یا نہیں.پھر آیتوں کے باہمی جوڑ کو دیکھیں گے کہ اُن کے لحاظ سے وہ معنی کہاں تک موزون ہیںپھر سیاق دیکھیں گے کہ اس کے مطابق وہ بنتے ہیں یا نہیں.اس کے بعد اگلی آیتوں کو دیکھیں گے کہ اُن کے ساتھ ان معنوں کی مناسبت سے پچھلی آیتوں کا کوئی جوڑ ثابت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا.غرض کئی باتوں کو دیکھا جائے گا اور کئی پہلوئوں سے ان معنوں پر غور کیا جائے گا اگر یہ معنے مطابقت کھائیں گے تو انہیں لے لیا جائے گا ورنہ ان کو ردّ کر دیا جائے گا.مثلاً یہی دیکھ لو وَ النّٰزِعٰتِ غَرْقًا سے مراد بعض نے وہ ستارے لئے ہیں جو ایک افق سے دوسرے افق کی طرف جاتے اور پھر دوسرے افق میںسے نکل آتے ہیں.اب یہ ایک معنے نَازِعَات کے نکال لئے جاتے ہیں مگر جب وَالنّٰشِطٰتِ نَشْطًا کے الفاظ آتے ہیں تو پھر بھی یہی معنی کئے جاتے ہیں کہ یہ ستارے ہیں جو ایک افق سے دوسرے افق کی طرف جاتے ہیں.اول تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں دو آیتیں بیان کی گئی ہیں مگر اُن کے دو معنے نہیں کئے جاتے بلکہ ایک ہی معنے کئے جاتے ہیں.نَازِعَات سے بھی ستاروں کا جانا اور واپس آنامراد لیا جاتا ہے اور نَاشِطَات سے بھی ستاروں کا جانا اور واپس آنا مراد لیا جاتا ہے.اب یہ کیسی عجیب بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بات نَازِعَات میں بیان کی تھی وہی اس نےنَاشِطَات میں بیان کر دی کوئی زائد بات اُس نے بیان نہیں کی یہ بات تو نہایت ردّی اور فصاحت سے گرے ہوئے کلام میں پائی جاتی ہے.خدا تعالیٰ کی کتاب تو ہر قسم کے نقائص سے منزّہ اور فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے دنیا کی تمام کتابوں پر فوقیت رکھتی ہے اُس میں ایسی بات کس طرح آسکتی ہے کہ نَازِعَات میں بھی وہ ستاروں کے آنے جانے کا ذکر کرے اور نَاشِطَات میں بھی وہ ستاروں کے آنے جانے کا ذکر کرے.یہ پہلا ثبوت ہمیں اس بات کا ملتا ہے کہ جو معنے ان الفاظ کے کئے گئے ہیں گو وہ لغت کے لحاظ سے تو درست ہوں مگر ان آیات میں وہ معنے مراد نہیں.ستاروں کا ذکر اس جگہ اسی صورت میں مراد لیا جا سکتا تھا کہ دونوں آیتوں کا الگ الگ مضمون ہوتا.ان مفسّرین کا اس بات پر مجبور ہونا کہ دونوں آیتوں کے ایک ہی معنے کریں بتاتا ہے کہ یہ معنے ہی غلط ہیں ورنہ اُن معنوں کے رو سے اگر وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا کو بالکل الگ کر دیا جائے تو وَالنَّزِعٰتِ غَرْقًا سے ہی وہ معنے نکل آتے ہیں جن کو وہ بیان کرنا چاہتے ہیں.وَ النّٰشِطٰتِ نَشْطًا کے الفاظ کی ضرورت ہی نہیں رہتی.اسی طرح وَ السّٰبِحٰتِ سَبْحًا کے یہ معنے کئے گئے ہیں کہ یہ ستارے ہیں جو افلاک میں دوڑتے پھرتے ہیں اور اس کا استدلال کُلٌّ فِیْ فَلَکٍ یَّسْبَحُوْنَ(الانبیاء:۳۴) والی آیت سے کیا جاتا ہے اور پھر فَالسّٰبِقٰتِ سَبْقًا کے بھی یہی معنے کر لئے جاتے ہیں کہ یہ ستارے ہیں جو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ قرآن کریم میں بڑا زور اس بات پردیا گیا ہے کہ ہر چیز اپنے اپنے دائرہ میں گردش کر رہی ہے یہ
Page 136
نہیں کہ سورج بھاگا بھاگا جا رہا ہو کہ کہیں چاند مجھے نہ پکڑ لے اورچاند اس ڈر سے دوڑ رہا ہو کہ کہیں مرّیخ مجھ پر قبضہ نہ پا لے.مگر ہمیں فَالسّٰبِقٰتِ سَبْقًا کے ایسے معنے بتائے جاتے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ گویا سورج اور چاند اور ستارے سب جاندار چیزیں ہیں اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی ہیں حالانکہ اگر سورج چاند کو پکڑ لے تو اس میں کیا فائدہ ہے نقصان ہی نقصان ہے کہ نظام شمسی تباہ و برباد ہو جائے گا ہمیں سباق اُن باتوں میں تلاش کرنا چاہیے جن میں دنیا کا نفع ہے نہ کہ اُن باتوں میں جن میں نقصان اور تباہی ہے.پھرفَالْمُدَبِّرٰتِ۠ اَمْرًاکے متعلق بھی کہا جاتا ہے کہ اس سے مراد نجوم ہیں حالانکہ قرآن کریم اور احادیث سے بالصراحت ثابت ہے کہ تدبیرِ امر خدا تعالیٰ کے اختیار میں ہے ستارے مد برات امر نہیں کہلا سکتے.چنانچہ رسول کریم صلے اللہ علیہ وآلہٖ وسلم فرماتے ہیں یَقُوْلُ اللّٰہُ (عَزَّوَجَلَّ) مَن قَالَ مُطِرْنَابِنَوْءٍ کَذَا وَکَذَا فَذٰلِکَ کَافِرٌ بِیْ مُؤْمِنٌ بِالْکَوْکَبِ (بخاری کتاب الاستسقاء باب قول اللہ تعالیٰ وتجعلون رزقکم انکم تکذبون)یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص کہتا ہے فلاں فلاںستارہ کے اثر کی وجہ سے بارش ہوتی ہے وہ میرا کافر ہے اور ستاروں کا مومن.گویا رسول کریم صلے اللہ علیہ وآلہٖ وسلم بفرمان خدا وندی ستاروں کی طرف تدبیر امر کی نفی کرتے ہیں مگر بعض مفسّرین یہ بتاتے ہیں کہ ان سے ستارے مراد ہیں.غرض اِن آیتوں کے جس قدر معنے کئے جاتے ہیں اُن میں سے بعض کو قرآن کریم بالنّص ردّ کرتا ہے اور بعض ایسے ہیں جو استدلال کی روشنی میں قابل قبول نہیں رہتے.اور بعض ایسے ہیں جن کو تسلیم کرنے کے نتیجہ میں بعض قرآنی الفاظ کو زائد قرار دینا پڑتا ہے اور کہنا پڑتا ہے کہ پہلےفقرہ کے جو معنے ہیں وہی دوسرے فقرہ کے ہیں حالانکہ قرآن کریم خدا تعالیٰ کا کلام ہے اور اس کا ہر لفظ حکمت پر مبنی ہے.پھر عجیب بات یہ ہے کہ نَازِعَات کے یہ معنے کئے جاتے ہیں کہ اس سے فرشتوں کے وہ گروہ مراد ہیں جو جسم کی گہرائیوں میں جا کر جان نکالتے اور پھر اسے باہر نکالتے ہیں.بعض کہتے ہیں اس سے مراد موتیں ہیں جو جان کونکالتی ہیں.کوئی کہتا ہے اس سے مرادنفوس ہیں جو سینہ میںغرق ہو جاتے ہیں یہ تو وَ النّٰزِعٰتِ غَرْقًا کے معنے تھے جب وَ النّٰشِطٰتِ نَشْطًاکے الفاظ آتے ہیں تو پھر یہ معنے کر لئے جاتے ہیں کہ اس سے مراد وہ نفوس ہیں جو قدموں سے نکالے جاتے ہیں.کوئی کہہ دیتا ہے یہ موت ہے جو نفوس انسانی کو نکالتی ہے.اس کے بعد وَ السّٰبِحٰتِ سَبْحًا کا ذکر آتا ہے تو پھر کہہ دیتے ہیں یہ ملائکہ ہیں جو مومنوں کی نرمی سے جان نکالتے ہیں.کوئی کہتا ہے اس سے مراد موت ہے جوجسم میں تیرتی ہے.چوتھے نمبر پرفَالسّٰبِقٰتِ سَبْقًا کا ذکر آتا تھا اس کے بھی یہ معنے کر لئے گئے ہیں کہ اس سے مراد ملائکہ ہیں جو مومنوں کی ارواح لے کر آگے نکل جاتے ہیں.کوئی کہتا ہے اس سے مراد موت ہے جو انسان کو
Page 137
دوڑکرجا کر پکڑتی ہے.آخر میں فَالْمُدَبِّرٰتِ۠ اَمْرًا کا ذکر آیا تھا اس کے متعلق بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ ملائکہ ہیں جو ملک الموت کے ساتھ آتے ہیں.گویا پانچ فقرے خدا تعالیٰ نے استعمال کئے مگر ہر جگہ انہوں نے یہی معنے کر لئے کہ اس سے مراد موت ہے.کوئی کہتا ہے قدموں میں سے جان نکالی جاتی ہے.کوئی کہتا ہے وہ تیر کی طرح انسانی جسم میں تیرتی ہے.کوئی کہتا ہے وہ انسان کو دوڑ کرآپکڑتی ہے حالانکہ وہ خواہ تیر کی طرح تیرے یا قدموں میں سے نکلے پھر ہوا کیا.اور بات کیا بنی کہ ہر جگہ موت کا ذکر شروع ہو گیا اور وہ بھی بالکل بے معنی.ایک فقرہ آتا ہے تو اس کے معنے بھی روح کے نکالے جانے کے کئے جاتے ہیں.دوسرا فقرہ آتا ہے تو اس کے معنے بھی روح کے نکا لے جانے کے کئے جاتے ہیں.تیسرا فقرہ آتا ہے تو اس کے معنے بھی روح کے نکالے جانے کے کئے جاتے ہیں.یہ بات کیا ہوئی اور قرآن کا مقصد کیا ہوا کہ بار بار روح کے قبض کا ذکر بغیر کسی مزید مقصداور فائد ہ کےکرتا ہے.آخر اس سے بنی نوع انسان کو کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے یا اُن کے علم میں اس سے کیا اضافہ ہو سکتا ہے یا کون سی پیشگوئی ہے جو اِن معنوں میں نظر آتی ہے.کون سا ـغیب ہے جو ان الفاظ میں ظاہر کیا گیا ہے یا کون سی ترقی ہے جو ان معنوں میں علمِ سائنس میں ہوتی ہے یا علم الاخلاق میں ہوتی ہے یا علم روحانیت میں ہوتی ہے.آخر ہواکیا؟ جان قدموں میں سے نکلے یا ہاتھ پائوں میں سے نکلے بہرحال جو مر گیا وہ مر گیا ہمیں اس سے کیا بحث ہے کہ اس کی جان قدموں سے نکلی تھی یا سر میں سے نکلی تھی.مگر کوئی حکمت نہیں بتائی جاتی اور اندھا دُھند خدائی کلام کے پانچ فقروں کے مسلسل یہ معنے کئے جاتے ہیں کہ اس سے موت ہی مراد ہے اور کچھ مراد نہیں.پھر خود ایک ایک آیت کے جو معنے کئے گئے ہیں اُن میں بڑا اختلاف ہے.معاذ بن جبل سے ابن مردویہ نے جو حدیث نقل کی ہے اُس میں یہ بتایا گیا ہے کہ نَاشِطَاتِ دوزخ کے وہ کُتّے ہیں جو دوزخیوں کا گوشت نوچیں گے اور دوسرے کہتے ہیں اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو مومنوں کی جان نکالتے ہیں.یہ کتنے متضاد معنے ہیں کہ ایک شخص کہتا ہے یہ دوزخ کے وہ کُتّے ہیں جو دوزخیوں کا گوشت نوچیں گے اور دوسرا کہتا ہے اس سے وہ ملائکہ مرادہیں جو مومنوں کی جان نکالتے ہیں.نازعات اور ناشطات سے مرادفرشتوں کے گروہ ان ساری باتوں سے معلوم ہو تا ہے کہ کسی ایک امرپر مفسّرین کا اتفاق نہیں ہوا بلکہ ہر بات میں اختلاف پایا جاتا ہے.صرف ایک معنے ہیں جس پر اتفاق پایا جاتا ہے اور وہ معنے فرشتوں کے ہیں.اکثر صحابہ اور تابعین اور اُن کے بعد آنے والے مسلمان زیادہ تر اسی امر پر متفق نظر آتے ہیں کہ نَازِعَات ا ور نَاشِطَاتِ سے مراد فرشتوں کے گروہ ہیں لیکن اس میں ایک دِقّت ضرور ہے اور وہ یہ کہ
Page 138
ان معنوں کے لحاظ سے بھی یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ جو بات نَازِعَات میں بیان کی گئی تھی وہی نَاشِطَاتِ میں بیان کی گئی ہے.چنانچہ وہ کہتے ہیں نَازِعَات سے مراد بھی فرشتوں کے گروہ ہیں جو جان نکالتے ہیں اور نَاشِطَاتِ سے مراد بھی فرشتوں کے گروہ ہیں جو جان نکالتے ہیں گویا ان معنوں کو تسلیم کرلینے کی صورت میں پھر بھی یہ دِقّت باقی رہے گی کہ جو بات ایک آیت کے ذریعہ ادا کی جا سکتی تھی اس کے لئے دو آیتیں کیوں لائی گئی ہیں پس یہ ایک دِقّت ضرور ہے لیکن جہاں تک محل کا سوال ہے ان آیات کے معنوں میں فرشتوں کا تسلیم کرناکوئی بعید بات نہیں بلکہ قرین قیاس ہے اور آیتوں کا مضمون اس کی تائید کرتا ہے لیکن جیسا کہ میں نے بتایا ہے یہ نقص ضرور ہے کہ اس کی تفاصیل میں مفسّرین نے بعض ایسی باتیں بیان کی ہیں جن کے متعلق یہ اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ اُن میں بلا وجہ تکرار سے کام لیا گیا ہے.اِس میں کوئی شبہ نہیں کہ قرآن کریم میں بعض مقامات میں تکرار بھی پایا جاتا ہے مگر وہی تکرار مفید ہوتا ہے جو زائد معنے دیتا ہو.اور اگر اُس تکرار کو اُڑا دیا جائے تو ساتھ ہی مضمون کے وہ زائد معنے بھی اُڑ جاتے ہوں لیکن جہاں ایسے معنے نہ ہو سکیں وہاں کلام الٰہی میں تکرار ایک عیب کی چیز ہے.بہرحال اگر اس نقص کو دُور کر کے اِن معنوں کو قرآن کریم کی اِن آیات پر چسپاں کیا جا سکے تو اس میںکوئی شبہ نہیں کہ یہ معنے بالکل قرین قیاس اور آیات کے مضمون کے مطابق ہوں گے.نازعات سے مراد غازیوں کے گروہ تیسرے معنے جن کی طرف سب سے کم توجہ دی گئی ہے مگر درحقیقت وہ سب سے زیادہ اِن آیات پر چسپاں ہوتے ہیں اور جن کی طرف تفاسیر میں اشارہ بھی پایا جاتا ہے وہ یہ ہیں کہ ان میں نَازِعَاتِ سے مراد وہ غازی ہیں جو تیر اندازی کرتے اور غزوات میں اپنے گھوڑے دوڑاتے ہیں.یہ معنے سب سے زیادہ قرین قیاس ہیں لیکن انہی معنوں کی طرف سب سے کم مفسّرین نے توجہ کی ہے پس اگر اُن کے اس فقرہ پر ہم کوئی عمارت کھڑی کر سکیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کچھ حصہ پُرانے مفسّرین کا بھی ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ہی اس کے موجد ہیں بلکہ ہمیں اس بارہ میں پُرانے مفسّرین کی راہنمائی کو تسلیم کرنا پڑتا ہے.میں بتا چکا ہوں کہ ان آیات پر ملائکہ کے معنے بھی چسپاں ہو سکتے ہیں جس کی طرف اکثر صحابہ اور تابعین اور بڑے بڑے مسلمانوں کا خیال گیا ہے اسی طرح ان آیات میں غازی بھی مراد لئے جاسکتے ہیں اور گو ہم نہیں کہہ سکتے کہ تابعین سے یہ معنے مروی ہیں مگر بہرحال مفسّرین نے اس خیال کا اظہار کیا ہے اور یہ معنے بھی یقیناً ایسے ہیں جو اس مقام پر چسپاں ہو سکتے ہیں اور اُن کا اس پہلو کے متعلق خیال پیدا کر دینا بھی ایک بہت بڑی خوبی ہے.بیشک دفعہ بعض دفعہ عمارت بنانی بھی بڑی مشکل ہوتی ہے مگر عام طور پر عمارت بنانی اتنی مشکل نہیں ہوتی جتنی راہنمائی مشکل
Page 139
ہوتی ہے.پس یہ دو معنے ایسے ہیں جو قرینِ قیاس او ر موقعہ ومحل کے مطابق ہیں.گو ان معنوں کو آیات پر چسپاں کرتے ہوئے مفسّرین سے بہت کچھ غلطیاں بھی ہوئی ہیں.مثلاً فرشتوں کے معنے توانہوں نے لے لئے ہیں مگر اُن معنوں کو ایسے رنگ میںچسپاں کیا ہے جس میں اضطراب پایا جاتا ہے.کہیں آیتوں کا باہمی جوڑ نہیں ملتا.کہیں ترتیب میں نقص پیدا ہو جاتا ہے.کہیں بلا وجہ تکرار تسلیم کرنا پڑتا ہے.بہرحال اگر ہم ان معنوں کو پسند کرتے ہیں تو ان مشکلات کو حل کرنا ہمارا کام ہے.اب پیشتر اس کے کہ میں اِن آیات کے متعلق اپنی تشریح بیان کروں یہ امر واضح کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ اس جگہ چار فقروں میں مفعول مطلق استعمال ہوئے ہیں اور پانچویں فقرہ میں مفعول بہٖ آیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَ النّٰزِعٰتِ غَرْقًا.وَّ النّٰشِطٰتِ نَشْطًا.وَّ السّٰبِحٰتِ سَبْحًا.فَالسّٰبِقٰتِ سَبْقًا.فَالْمُدَبِّرٰتِ۠ اَمْرًا.اِن میں سے پہلے چار فقروں میں غَرْقًا.نَشْطًا.سَبْحًا اور سَبْقًا مفعول مطلق کے طور پر استعمال ہوئے ہیں اور اَمْرًا مُدَبِّرَات کا مفعول بہٖ کے طور پر.جہاں تک فَالْمُدَبِّرٰتِ۠ اَمْرًا کا تعلق ہے وہ تو زیر بحث نہیں لیکن باقی چار جگہوں میں مصدر آئے ہیں اُن کے متعلق یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ تین مصدر تو انہی افعال سے آئے ہیں جو پہلے آچکے ہیں مثلاً نَاشِطَات کا نَشْطًا ہے سَابِحَات کا سَبْحًا ہےاور سَابِقَات کا سَبْقًا ہے مگر نَازِعَات کے مقابلہ میں غَرْقًا رکھ دیا گیا ہے حالانکہ نَزَعَ کا مصدر نَزْعًا ہے یا نُزُوْعًا ہے یا نَزَاعَۃً وَنِزَاعًا ہے مگر بجائے اس کے کہ ان میں سے کوئی ایک مصدر رکھا جاتا ان کی بجائے باہر سے ایک اَور لفظ لے لیا گیا ہے اور نَازِعَات کے ساتھ غَرْقًا کا لفظ رکھ دیا گیا ہے.قرآن مجید کی بعض آیات کے صحیح معنے سمجھنے کا ایک گر اس کے متعلق یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ یہ بہت بڑی حکمت کی بات ہے عربی زبان میں صرف فعل سے معنے متعین نہیں ہوتے بلکہ فعل کو اس کے مصدر سے باندھ کر معنے پیدا ہوتے ہیں مثلاً اگر ہم صرف نَزَعَ کہہ دیں تو خالی نَزَعَ کے معنے یہ بھی ہوں گے کہ کسی چیزکو اُکھیڑ دیا.یہ معنے بھی ہوں گے کہ فلاں شخص ایک بات سے رُک گیا.یہ معنے بھی ہوں گے کہ اُس نے کسی چیز کی خواہش کی.لیکن جب اس کو کسی مصدر سے باندھ دیا جائے گا تو اس کے وہی معنے ہوں گے جو اس مصدر سے ظاہر ہوتے ہوں گے.مثلاً ہم نَزَعَ نَزْعًا کہیں گے تو اس کے معنے مشابہ ہو جانے کے نہیں ہوں گے کیونکہ مشابہ ہونے کے معنے نُزُوْعًا مصدر سے پیدا ہوتے ہیں یا اس کے معنے شوق اور خواہش پیدا ہونے کے نہیں ہوں گے کیونکہ یہ معنے اُس وقت پیدا ہو سکتے ہیں جب نَزَ اعَۃً وَنِزَاعًا وَنُزُوْعًا مصدر ہو بلکہ نَزَعَ نَزْعًا کے معنے کسی چیز کو اُکھیڑ دینے یا کسی کو معزول کر دینے کے ہوں
Page 140
گے یا اَور دوسرے معنے ہوں گے جو اس مصدر سے پیدا ہوتے ہیں.تو مصدر معنوں کی تعیین کر دیا کرتا ہے.فعل کی شکل ایک ہوتی ہے لیکن مصدر مختلف ہونے سے ان کے معنے بدلتے چلے جائیں گے.اب اگر قرآن کریم میں وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا کی بجائے وَالنَّازِعَاتِ نَزْعًا ہوتا تو اس کے معنے صرف اتنے ہوتے جو نَزْعًا مصدر کی صورت میں نَزَعَ کو حاصل ہوتے ہیں یا اگر وَالنَّازِعَاتِ نَزْعًا کی بجائے وَالنَّازِعَاتِ نُزُوْعًا ہوتا پھر نَازِعَات کے وہ معنے ہوتے جن پر نُزُوْعًا کا مصدر دلالت کرتا ہے یا اگر نَازِعَات کے ساتھ نِزَاعًا آجاتا تو پھر وہ معنے ہوتے جو نَزَعَ نَزَاعَۃً وَنِزَاعًا سے ظاہر ہوتے ہیں تو عربی زبان میں مصدرکا دہرانا محض تاکید کے لئے نہیں ہوتا بلکہ معنوں کی تعیین کے لئے بھی ہوتا ہے لیکن جب کسی فعل کا مصدر نہ آئے بلکہ باہرسے کوئی لفظ آجائے جیسے وَالنَّازِعَات کے ساتھ غَرْقًا رکھ دیا گیا ہے تو اس کے معنے یہ ہوں گے تمام مصدروں کے معنوں میں سے جو بھی اس جگہ چسپاں ہو سکتے ہوں مراد لئے جا سکتے ہیں.اگرنَازِعَات کے ساتھ نَزْعًا مصدر ہوتا تو ہم صرف وہ معنے کرتے جو نَزْعًا سے ظاہر ہوتے ہیں.اگر نُزُوْعًا مصدر ہوتا تو ہم صرف وہ معنے کرتے جو نُزُوْعًا سے ظاہر ہوتے ہیں.اگر نَزَاعَۃً یا نِزَاعًا مصدر ہوتا تو ہم صرف وہ معنے کرتے جو نَزَاعَۃً یا نِزَاعًا سے ظاہر ہوتے ہیں اور اس طرح آیت کے معنے محدود ہو جاتے لیکن جب وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا کہہ دیا گیا تو اس کے معنے یہ ہوئے کہ نَزَعَ کے سارے مصادر کے معنے اس مقام پر چسپاں ہو سکتے ہیں گویا اِس طریق سے اس طر ف اشارہ کیا گیا ہے کہ تم سب معنوں کو دیکھو اور پھر غور کرو کہ اس آیت کے کیا معنے ہیں.اسی طرح آگے آتا ہے وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا اس کے بھی دو مصدر ہیں ایک نَشَطَ یَنْشُطُ نَشَاطًا اور ایک نَشَطَ یَنْشُطُ نَشْطًا یہاں نَشْطًا کہہ کر معنوں کو وسیع نہیں کیا بلکہ ان کو محدود کر دیا گیا ہے اور بتا دیا گیا ہے کہ اس آیت کے وہی معنے ہو سکتے ہیں جن پر نَشْطًا مصدردلالت کرتا ہے نَشَاطًا مصدر و الے معنے اس مقام پر چسپاں نہیں ہو سکتے پاس ہم اس آیت کے جب بھی معنے کریں گے نَشْطًا مصدر کو مدنظر رکھیں گے.اور اُن معنوں کی طرف نہیں جائیں گے جو نَشَاطًا سے ظاہر ہوتے ہیں.سورۃ نازعات کی پہلی پانچ آیتوں کی صحیح تفسیر اب میں پانچوں آیتوں کے متعلق اپنا نقطہ نظر پیش کرتا ہوں.میں بتا چکا ہوں کہ ایک معنے جو میرے نزدیک معقول ہیں اور جن پر اکثر صحابہ ؓ اور تابعین اور تبع تابعین کا اتفاق ہے اور جو اکثر مفسّرین سے بھی مروی ہیں وہ یہ ہیں کہ اس جگہ ملائکہ مراد ہیں.مگر یہاں یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ ملائکہ کی طرف تو مذکّر کی ضمیر جانی چاہیے تھی جیسے قرآن کریم میں ایک اور جگہ یَفْعَلُوْنَ مَا یُؤْمَرُوْنَ (النحل :۵۱) کہہ کر ملائکہ کی طرف مذکر کی ضمیر پھیری گئی ہے مگر یہاں مذکر کی بجائے مؤنث کی ضمیر آتی ہے حالانکہ ملائکہ مؤنث
Page 141
نہیں ہیں.اس کے متعلق صحابہؓ کے کسی جواب کا تو مفسّرین ذکر نہیں کرتے مگر انہوں نے خود اس اشکال کو دور کرنے کی کوشش کی ہے.وہ کہتے ہیں کہ گو فرشتوں کے لئے ضمیر مذکر آنی چاہیے تھی مگر اس جگہ فرشتوں سے مراد طوائف الملائکہ یعنی فرشتوں کے گروہ ہیں اور چونکہ ضمیر طوائف کی طرف جاتی تھی اس لئے یہاں مؤنث کی ضمیر لائی گئی ہے مذکر کی ضمیر نہیں لائی گئی.چنانچہ تمام مفسّرین اور ادیب اس امر پر اتفاق رکھتے ہیں کہ وَ النّٰزِعٰتِ غَرْقًا اور وَ النّٰشِطٰتِ نَشْطًاسے طوائف الملائکہ یعنی فرشتوں کے بہت سے گروہ مراد ہیں اور چونکہ نَازِعَات میں جمع کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اس لئے معنے یہ ہوں گے کہ فرشتوں کے گروہ در گروہ.پس چونکہ اکثر صحابہؓ اور تابعین اور تبع تابعین اور پھر مفسّرین بھی اس بات پر متفق ہیں کہ اس جگہ ملائکہ کی طرف اشارہ ہے اس لئے لازمًا وہ اس امر پر بھی متفق سمجھے جائیں گے کہ ضمیر مؤنث طائفہ کی وجہ سے لائی گئی ہے یعنی نَازِعَات سے مراد طَوَائِفٌ مِّنَ الْمَلٰئِکَۃِ ہیں.جہاں تک اس نقطہ نگاہ والوں کا سوال ہے جن میں اکثر صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین شامل ہیں یہ امر پایۂ ثبوت کو پہنچ جاتا ہے کہ یہ خیال کہ کوئی ایک فرشتہ جسمانی طور پر اتر کر دنیا کے سب کام کرتا ہے خلافِ شریعت اور خلاف عقیدۂ قرآن ہے اگر عززائیل ہر شخص کے پاس جا کر اس کی جان نکالتا ہے تو پھر جان نکالنے کے لئے کسی طائفہ کی کیا ضرورت ہے طائفہ کی تو اُسی جگہ ضرورت ہوتی ہے جہاں کام ایک کی طاقت کا نہیں ہوتا یامتعدد کام ہونے کی وجہ سے متعدد کام کرنے والوں کی ضرورت ہو.پس یا تو یہ ماننا پڑے گا کہ عزرائیل میں لوگوں کی جان نکالنے کی طاقت نہیں اسی لئے وہ لوگوں کی جان نکالنے کے لئے اپنے ساتھ ایک جتھہ لے کر جاتا ہے اور یا پھر یہ ماننا پڑے گا کہ جان نکالنے والا طائفہ مختلف انسانوں کی اپنے اپنے رنگ میں جان نکالتا ہے.اسی طرح باقی کاموں کے متعلق سمجھا جائےگا ورنہ اگر یہی خیال کیا جائے کہ ایک فرشتہ ہی زمین پر اتر کر تمام کام کرتا ہے تو یہ عقیدہ اسلام کے خلاف ہو گا کیونکہ اول تو ہبوطِ جسمانی ہر جگہ پر ایک شرک کے مشابہ عقیدہ ہے گویا اس طرح ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ایک ہی فرشتہ ایک ہی وقت میں حاضر بھی ہے اور غائب بھی ہے یہاں بھی ہے اور وہاں بھی ہے اور ہر جگہ ہے.گویا محیطِ کُل ہونے اور ایک ہی وقت میں عرش وفرش پر ہونے میں وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا شریک ہے نعوذ باللہ من ذالک.دومؔ ہبوط جسمانی کی ضرورت تو مادی اجسام میں ہوتی ہے ملائکہ تو روحانی اجسام ہیں اور ارواح لطیفہ اپنی شعائوں سے زیادہ کام کرتی ہے بہ نسبت اپنے جسم کے بدلنے کے.دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی جتنی کوئی چیز لطیف ہوتی چلی جاتی ہے وہ بجائے اپنے مقام بدلنے کے شعاعوں سے کام لیتی ہے پس جیسا کہ ان آیات سے (جن کے ملائکہ کی نسبت ہونے پر سب متفق ہیں) ظاہر ہے ایک ایک کام پر ایک گروہ ملائکہ مقرر ہے جس کے دوسرے لفظوں میں یہ معنی ہیں کہ
Page 142
ملائکہ کا کام محدود ہوتا ہے اور پھر دائرہ عمل بھی محدود ہوتا ہے ایک کام جو ایک گروہ کے سپرد ہوتا اُسے ایک گروہ کرتا ہے نہ کہ کوئی ایک فرشتہ اور جب یہ حالت ہے تو ماننا پڑے گا کہ ہر گروہ کا کوئی مرکز بھی ہے اور اُس مرکز کے ساتھ اس کے افراد کے تعلقات ہیں اور وہاں وہ اپنے افسر کو رپورٹ دیتے ہیں بے شک انسانوں کی طرح نہیں بلکہ اسی طرح پر جو ملائکہ کے شایان شان اور مناسب حال ہے.(ملائکہ کے انتظام اور کام کے متعلق تفصیل کے لئے دیکھئے توضیح مرام طبع پنجم صفحہ ۱۵ تا آخر) النّٰزِعٰتِ غَرْقًاکا صحیح حل اس تمہید کے بعد مَیں پہلے نَازِعَات کو لیتا ہوں اور اس کی تشریح کرتے ہوئے فرشتوں والے معنوں کو مقدم کر لیتا ہوں کیونکہ اس پر اکثر صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین اور مفسّرین کا اتفاق ہے.نازعات سے مراد طوائف الملائکۃ نَازِعَات کے ایک معنے اُکھیڑنے والی جماعتوں کے ہیں کہتے ہیں نَزَعَ الشَّیْءَ عَنْ مَّکَانِہٖ اَیْ قَلَعَہٗ.یعنی کسی چیز کو اپنی جگہ سے اُکھیڑا.پس ان معنوں کے رُو سے نَازِعَات کے معنے ہوں گے اپنی اپنی جگہ سے بعض چیزوں کو اکھیڑنے والے فرشتوں کے متعدد گروہوں کو ہم بطور شہادت پیش کرتے ہیں.اوّلؔ تو اس ترجمہ سے اُس تمہید پر جسے میں بیان کر چکا ہوں مزید روشنی پڑتی ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ نہ صرف ایک گروہ فرشتوں کا نَزْعٌ کے کام پر مقرر ہے بلکہ خود نَزْعٌ کا کام مختلف اقسام کا ہے اور ہر کام پر الگ قسم کا گروہ مقرر ہے گویا یہاں سے فرشتوں کے گروہ در گروہ ہونے کا مسئلہ معلوم ہوتا ہے اورپتہ لگتا ہے کہ نَزْعٌ کے کام کے لئے کئی گروہ ہیں اورنَزْعٌ کی ہر قسم پر ایک ایک گروہ مقرر ہے اس سے معلوم ہوا کہ درحقیقت ہر سبب کا مسبب ایک فرشتہ ہوتا ہے اور چونکہ اسباب بے انتہاء اور لَا تُعَدُّوَ لَاتُحْصٰی ہیں اس لئے فرشتے بھی اَنْ گنت ہیں.اسی لئے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ مَایَعْلَمُ جُنُوْدَ رَبِّکَ اِلَّا ھُوَ (المدثر :۳۲)فرشتوں کی تعداد کا اندازہ انسان نہیں لگا سکتا.جس طرح دنیا کے کاموں میں باریک در باریک اسباب کا سلسلہ چلتا چلا جاتا ہے جن کا کوئی انسان اندازہ بھی نہیں لگا سکتا اسی طرح اُن پر جو ملائکہ مقرر ہیں ان کا بھی کوئی انسان اندازہ نہیں لگا سکتا.ملائکہ کی مدد سے مسلمانوں کی ترقی اس آیت میں جو فرمایا کہ اپنی جگہ سے اکھیڑنے والے متعدد گروہ تو اس میں اکھیڑنے سے مراد کفّار کے اُن دلوں کا اُکھیڑنا ہے جو بظاہر کافر لیکن بباطن اسلام سے مناسبت رکھتے تھے.اس کا ثبوت یہ ہے کہ اس سے پہلی سورۃ میں غلبۂ اسلام اور غلبۂ قرآن کا ذکر تھا اور اس غلبہ کو قیامت کا ثبوت قرار دیا گیا تھا پس اس ترتیب کے مطابق یہ ضروری تھا کہ اس سورۃمیں یہ بتایا جاتا کہ یہ غلبہ کس طرح ہو گا.اسلام کس طرح ترقی کرے گا اور کفر کی بنیادوں کو کس طرح اکھیڑا جائے گا اسی لئے اس کو وَ النّٰزِعٰتِ غَرْقًا سے شروع کیا گیا اور بتایا گیا
Page 143
کہ کفار کے دل جو بظاہر اسلام سے عناد رکھتے ہیں لیکن بباطن اسلام کی خوبیوں کے قائل ہیں ان کو اکھیڑنے کے لئے فرشتوں کے متعدد گروہ کام کریں گے چنانچہ واقعہ یہی ہے کہ اُن میں سے کوئی شخص کسی وجہ سے مخفی طور پر کفر سے بیزار تھا اور کوئی کسی وجہ سے.کوئی ان کی وحشت کی وجہ سے بیزار تھا اور کوئی بد انتظامی کی وجہ سے.کوئی ظلم کی وجہ سے بیزار تھا اور کوئی شریعت نہ ہونے کی وجہ سے.اور اس طرح گو کچھ لوگ کفر کے باغ کے درخت تھے مگر اُن کی جڑیں اس زمین میں کھوکھلی ہو چکی تھیں اور اب اُن کی کفر کی سرزمین سے مناسبت نہیں رہی تھی جب محمد صلے اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تعلیم دنیا کے سامنے پیش کی تو ہر خُلق پر مقرر فرشتے نے اپنے اپنے دائرہ کے باغ کو چُنا اور اُن کے نیک جذبات کو ابھارنا شروع کیا.محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کامل تعلیم لائے تھے اُس میں شرک نہ تھا.توحید تھی.جہالت نہ تھی.علم تھا.ظلم نہ تھا.انصاف تھا.وحشت نہ تھی.رأفت تھی.مادر پدر آزادی نہ تھی.ایک باقاعدہ اور مفید قانون تھا.بدانتظامی نہ تھی.انتظام تھا.غرض ہر قسم کی ضرورت جو انسانی فطرت کو پیش آسکتی تھی اس کا سامان آپ کی تعلیم میں موجود تھااور ہر غلطی جو کفر میں موجود تھی اس کی اصلاح کا سامان بھی موجود تھا.پس ہر فرشتہ جو کسی خلق پر مقرر تھا اُس نے ہر دل میں جو اس کے مطابق حال تھا اپنے دائرہ کے مطابق نیک جذبات کو اُبھار کر اس نیکی کو نمایاں کرنا شروع کر دیا جس کی وجہ سے کفر کا وُہ نقص اُسے بہت ہی بھیانک نظر آنے لگا.مثلاً ایک شخص اگر شرک کو ناپسند کرتا تھا تو محمد صلے اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے بعد توحید کے قیام کے لئے جو فرشتے مقرر تھے انہوں نے اِن تھوڑی نفرت رکھنے والے لوگوں کے دلوںمیں مزید نفرت پیدا کرنی شروع کر دی اور شرک کی خرابی اُن پر اور زیادہ واضح کر دی.دوسری طرف انہوں نے اپنے اپنے دائرہ کی نیک تعلیم جو اسلام میں تھی اسے ان لوگوں کے قریب الفہم بنایا.نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اپنے باغ سے اور زیادہ دل برداشتہ ہو گئے اور جس زمین میں وہ ٹکے ہوئے تھے اُس سے اور بھی نفرت کرنے لگے.انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ یہ زمین ہمارے مناسب حال نہیں اور باغ محمدیؐ میں جانے کے بے انتہاء شائق ہو گئے.جب یہ حالت پیدا ہوگئی.پہلا قدم فرشتوں نے اٹھا لیا اور لوگوں کے دلوں میں کفر سے نفرت پیدا کردی اور جو شخص جس نیکی کی طرف مائل تھا اُسے اُس نیکی کی طرف انہوں نے اور زیادہ مائل کر لیا اور اس طرح اسلام کی محبت اُن کے دلوں میں پیدا کر دی.تو اس کے بعد ہر گروہ کے فرشتوں نے دوسرا کام شروع کیا جس کا وَ النّٰشِطٰتِ نَشْطًا میں ذکر آتا ہے.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَ النّٰشِطٰتِ نَشْطًا قسم ہے اُن طوائفِ ملائکہ کی جو گرہیں باندھتے ہیںیعنی وہ وہاں سے اُن ارواح کو کاٹ کر محمد رسول اللہ صلے اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کے دامن سے باندھنا شروع کر دیں گے.پہلے اُن فرشتوں
Page 144
کا ذکر کرنے سے جو قَلَعکرتے ہیں یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرا گروہ پہلا عمل نہیں کرتا بلکہ مطلب یہ ہے کہ جب وہ پہلا عمل کر لیں گے تو پھر یہ دوسر ا کام شروع کر دیں گے.یعنی کفر سے بیزار کرنے کے مرحلہ کے بعد ان کے اندر ایمان کی محبت پیدا کریں گے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لا کر وابستہ کر دیں گے بیعت بھی باندھنا ہی کہلاتا ہے.چنانچہ رسول کریم صلے اللہ علیہ وآلہٖ وسلم فرماتے ہیں مَنْ مَّاتَ وَلَمْ یَکُنْ فِیْ عُنُقِہٖ بَیْعَۃٌ فَمَاتَ مِیْتَۃَ الْجَاھِلِیَّۃِ (مسلم کتاب الامارۃ باب وجوب ملازمۃ جماعۃ المسلمین عند الفتن فی کل حال) اور نَشْطٌ کے معنے بھی ہیں عَقْدُ الْحَبْل یعنی باندھنا.پس وَ النّٰشِطٰتِ نَشْطًا کے معنے یہ ہوئے کہ اُن لوگوں کو جو پہلے کفر سے بیزار ہو جائیں گے ان کے متعلقہ فرشتے اسلام کی طرف راغب کر کے آخر محمد رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی رسّی میں لا کر باندھ دیں گے.پھر فرمایاوَ السّٰبِحٰتِ سَبْحًا اور قسم ہے اُن ملائکہ کے گروہوں کی جو تیرتے ہیں اور تیرتے تیرتے دُور نکل جاتے ہیں اِس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اسلام کی ترقی کے لئے ملائکہ صرف مکّہ میں کوشش نہ کریں گے بلکہ جو مستعد روحیں مکّہ میں ہوں گی ان کو اسلام کی طرف لا کر وہ دوسرے علاقوں میں نکل جائیں گے اور وہاں جو مستعد ارواح ہوں گی انہیں اسلام کی طرف لائیں گے چنانچہ ملائکہ کی اس پرواز کا ہی نتیجہ تھا کہ ابو ذر غفاری ؓ قبیلہ غفار سے اور وفدِانصار مدینہ سے اسلام لایا.ابو موسیٰ اشعری اور اُن کے ساتھ تعلق رکھنے والا گروہ یمن سے آیا اور سلمان فارسی فارس سے آئے اور اس طرح ایک وقت میں اسلام کے مختلف اکناف میں پھیلنے کا سامان ہو گیا.مختلف فرشتوں کے گروہوں کا اثر صحابہ پر اس کے بعد فرمایافَالسّٰبِقٰتِ سَبْقًا.پھر انہوں نے مقابلہ شروع کیا کہ کون بڑھتا ہے یعنی جب مختلف علاقوں میں ملائکہ قلوبِ مومنین فتح کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو ہر علاقہ میں مسابقت کی رُوح پیدا ہو جائے گی اور ہر طبقہ اور ہر علاقہ کے ملائکہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے چنانچہ ملائکہ کے اضلال مومنین کے کاموں سے ہم دیکھتے ہیں کہ اُن میںایک دوسرے سے بڑھنے کی بے انتہاء تڑپ تھی اور ہر قوم دوسروں سے آگے نکلنے کی خواہش مند تھی چنانچہ زمانۂ خلافتِ اولیٰ اور ثانیہ میں اس کی اکثر مثالیں ملتی ہیں.خود زمانۂ نبویؐ میں جب مسلمانوں کی جماعت نہایت چھوٹی سی تھی.اس مسابقت کی روح کا کئی مثالوں سے اچھی طرح پتہ لگ جاتا ہے قوموں کے لحاظ سے مہاجر اور انصار گو دانت کاٹی روٹی کھاتے تھے اور بھائیوں سے بھی زیادہ وہ ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے مگر دین کی خدمت میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ ان میں شدید طور پرپایا جاتا تھا.پھر انصار کے خود دوقبیلے تھے اوسؔ اور خزرجؔ.وہ آپس کی لڑائی کو
Page 145
بھول چکے تھے.وہ اسلام میں داخل ہو کر بھائی بھائی بن گئے تھے.مگر دین میں مسابقت کی رُوح اُن میں ایسی پیدا ہوگئی تھی کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو مجھے میرے دشمن کی تکلیف سے بچانے کے لئے آگے بڑھے اورآپ کا مطلب اس سے کعب بن اشرف شدید دشمنِ اسلام تھا تو اوس میں سے ایک جماعت کھڑی ہو گئی اور اُس نے کہا یا رسول اللہ ہم اس کام کے لئے تیار ہیں چنانچہ آپ نے وہ کام اُن کے سپرد کیا اور انہوں نے اس دشمنِ اسلام کو عام جنگی قواعد کے مطابق(نہ کہ ظلم سے) مار دیا (سیرۃ النبویۃ لابن ہشام اجزٗ الثالظ زیر عنوان مقتل کعب بن اشرف)(یہ تفصیل کا موقع نہیں.دشمنانِ اسلام اعتراض کیا کرتے ہیں کہ آپ نے ناجائز طور پر اس کو قتل کرایا تھا لیکن اُن کا یہ الزام خلافِ تاریخ ہے.تفصیلی بحث کے لئے دیکھو تفسیر کبیر جلد دوم صفحہ ۱۹۸) جب کعب مارا گیا تو وہی مسابقت کی روح کہ اسلام میں ہم ایک دوسرے سے بڑھ کر رہیں دوسرے گروہ کے دل میں پیدا ہوئی چنانچہ قبیلہ خزرج کے لوگ رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ اب ہمیں بھی کوئی ایسا ہی کام دیجئے تاکہ ہم بھی اپنے بھائیوں سے پیچھے نہ رہیں اور آخر رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم نے ابو رافع کو قتل کرنے کا کام اُن کے سپرد کیا اور اس قبیلہ نے اس دشمنِ اسلام کو جا کر مارا (السیرۃ النبویۃ لابن ہشام الجزء الثالث زیر عنوان مقتل سلام بن ابی الحقیق ) پھر یہ مسابقت کی روح قبائل میں ہی نہ تھی قبیلوں سے جو چھوٹے چھوٹے خاندان تھے اُن میں بھی یہ روح پائی جاتی تھی چنانچہ انصار کے دونوں قبائل کے مختلف خاندان باری باری رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم کا رات کو پہرہ دیا کرتے تھے مگر وہ عام طور پر بغیر ہتھیار لگائے پہرہ دیا کرتے تھے.ایک دن رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم نے باہر ہتھیاروں کی آواز سنی اور پوچھا کہ یہ شور کیسا ہے کسی نے دریافت کر کے بتایا کہ فلاں خاندان کے لوگ ہتھیار بند ہو کر پہرہ دینے آئے ہیں.رسول کریم صلے اللہ علیہ وآلہٖ وسلم نے اُن کی اس روح مسابقت کو دیکھ کر پسند فرمایا.(بخاری کتاب الجہاد باب الحراسۃ فی الغزو...) سَابِقٰتِ سَبْقًاکے ماتحت مسلمانوں میں مسابقت کی روح پھر غریبوں اور امیروں میں مسابقت کی روح اس قدر پائی جاتی تھی کہ ایک دفعہ غرباء رسول کریم صلے اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ امیر لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں مگر ہم بوجہ مال نہ ہونے کے زکوٰۃ کے ثواب سے محروم ہیں.اسی طرح امراء صدقہ وخیرات کرتے ہیں مگر ہم یہ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس مال نہیں ہے.یا رسول اللہ ہمیں کوئی ایسی نیکی بتائیں جس پر عمل کر کے ہم اُن سے پیچھے نہ رہیں.رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ہر نماز کے بعد تینتیس دفعہ سُبْحَانَ اللّٰہ تینتیس دفعہ اَلْحَمْدُلِلّٰہ اور چونتیس دفعہ اللّٰہُ اَکْبَر کہہ لیا کرو کچھ دنوں کے بعد انہوں نے
Page 146
پھر شکایت کی کہ یا رسول اللہ اس بات کا کسی طرح امیروں کو بھی علم ہو گیا ہے اور وہ بھی ہر نماز کے بعد تینتیس تینتیس دفعہسُبْحَانَ اللّٰہ و اَلْحَمْدُلِلّٰہ اور چونتیس دفعہ اللّٰہُ اَکْبَر کہنے لگ گئے ہیں یا رسول اللہ آپ ان کو روکیں کہ وہ ایسا نہ کریں.آپ نے فرمایا میں اُن کو نیکی سے نہیں روک سکتا (مسلم کتاب المساجد و مواضع الصلوۃ باب استجاب الذکر بعد الصلوٰۃ) پھر یہ مسابقت کی روح صرف مردوں میں ہی نہیں پائی جاتی تھی بلکہ عورتوں میں بھی یہ روح کام کرتی نظر آتی تھی چنانچہ عورتوں نے ایک دفعہ احتجاج کیا کہ یا رسول اللہ مردوں میں تو آپ وعظ و نصیحت کرتے رہتے ہیں لیکن عورتوں کو یہ موقعہ نہیں ملتااس پر رسول کریم صلے اللہ علیہ وآلہٖ وسلم نے اُن کے لئے بھی ایک دن مقرر فرما دیا (بخاری کتاب العلم باب ھل یجعل للنساء یوم علی حدة فی العلم ) غرض مسلمانوںمیں کام کے متعلق یہ روح نہیں تھی کہ شکر ہے فلاں شخص نے کام کر لیا اور میرا بوجھ اُتر گیا بلکہ رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے تمام افراد میں یہ جوش پایا جاتا تھا کہ ہم دوسروں سے زیادہ ذمہ واری اپنے اوپر لیں.اور یہی قومی ترقی کا راز ہے.جب قو م کے افراد ذمہ واری کے مواقع پر دوسروں پر اس بوجھ کو ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ تباہ ہو جاتے ہیں.لیکن جب قوم کے ہر فرد میں یہ احساس ہو کہ زیادہ کام کرنے کا موقع مجھ کو ہی ملے تو وہ قوم ترقی کی طرف بڑھتی چلی جاتی ہے.صحابہؓ میں یہی مادہ پایا جاتا تھا جو اس بات کا ثبوت تھا کہ ان کےدلوں میں نیک تحریکیں کرنے والے ملائکہ میں بھی یہی روح پائی جاتی تھی.جب اسلام اَور پھیلا تو یہ مسابقت کی روح ایسی بڑھی کہ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ خلافتِ اُولیٰ اور خلافتِ ثانیہ کے زمانہ میں بعض قبائل نے اپنی ساری آبادی ہی جنگ میں فنا کر دی.وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ اسلام کے لئےاس موت کے قبول کرنے میں ہمارے ساتھ دوسرے بھی شریک ہوں.وہ ظاہری انعام وکرام میں تو دوسروں کو شریک بنانا چاہتے تھے مگر ملّی اور قومی قربانیوں میں ان کی خواہش یہی ہوتی تھی کہ موت کا پیالہ صرف ہم کو ہی ملے دوسروں کو نہ ملے.یہ اتنا لمبا مضمون ہے کہ تفسیر اس کی متحمل نہیں ہو سکتی.بہرحالفَالسّٰبِقٰتِ سَبْقًاکا یہ بیّن اور روشن ثبوت تاریخ کے صفحات پر موجود ہے.صحابہ کرام ؓ کے ذریعہ اس دنیا میں خدا کی بادشاہت کا قیام فَالْمُدَبِّرٰتِ۠ اَمْرًا میں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جب مسابقت والا کام ملائکہ کر لیں گے تو پھر ملائکہ مُدَبِّرَاتِ اَمْرًا ہو جائیں گے یعنی زمین پر انہی کی حکومت ہو جائے گی.کیونکہ ملائکہ نیک تحریکیں کرنے والے ہیں.جب زمین پر نیک لوگوں کی حکومت ہو جائے گی تو ہر محکمہ پر اُن لوگوں کا قبضہ ہو گا جو ملائکہ کی باتیں ماننے والے ہیں.نتیجہ یہ ہو گا کہ دنیا پر ملائکہ کی حکومت ہو جائے گی یا دوسرے لفظوں میں یوں کہو کہ خدا کی بادشاہت دنیا میں قائم ہو جائے گی کیونکہ ملائکہ کے متعلق آتا ہے یَفْعَلُوْنَ
Page 147
مَایُؤْمَرُوْنَ (النحل :۵۱) وہ وہی کرتے ہیں جو خدا کہتا ہے.پس ایسے انسانوں کی حکو مت کی وجہ سے جو ملائکہ کی بات مانتے ہیں دنیا پر ملائکہ کی حکومت ہو گی اور ان ملائکہ کی وجہ سے جو خدا کی ہر بات مانتے ہیں خدا کی بادشاہت دنیا میں قائم ہو جائے گی یا تیسرے لفظوں میں یہ کہہ لو کہ وہ دعا جو مسیح ؑ نے کی تھی کہ اے خدا ’’تیری بادشاہت آوے.تیر ی مرضی جیسی آسمان پر ہے زمین پر بھی بر آوے‘‘ (متی باب ۶ آیت ۱۰) وہ حضرت مسیح ؑ کے ذریعہ سے تو پوری نہ ہوئی کیونکہ جب تک اُن کی قوم نیک تھی بادشاہت نہ ملی اور جب بادشاہت ملی تو قوم مشرک ہو چکی تھی.مگر یہ دعا محمد صلے اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کے ذریعہ پوری ہوگئی.اُن کو اُسی وقت حکومت ملی جب اُن کے اتباع کےدل فرشتوں کے ہاتھ میں تھے اور وہ وہی کچھ دنیا میں کرتے تھے جو فرشتے اُن سے کہتے تھے اور فرشتے وہی کچھ کہتے تھے جو خدا تعالیٰ اُن سے کہتا تھا اِس طرح اُن کے زمانہ میں خدا تعالیٰ کی بادشاہت آسمان پر ہی نہ رہی بلکہ زمین پر بھی آگئی.کیسی شاندار اور زبردست یہ پیشگوئی ہے اور کس طرح دشمن بھی یہ اقرار کرنے پرمجبور ہے کہ خلفاء اسلام کی بادشاہت انسانی بادشاہت نہیں تھی بلکہ اخلاق کی حکومت تھی اور یہ الفاظ غیر مسلموں کے ہاں اسی حکومت کے لئے بولے جاتے ہیں جسے اسلامی اصطلاح میں فرشتوں کی حکومت کہتے ہیں اور کیوں نہ ہم اِسے فرشتوں کی حکومت کہیں کیا یوسف ؑ کو اِنْ ھٰذَا اِلَّا مَلَکٌ کَرِیْمٌ (یوسف:۳۲ )نہیں کہا گیا تھا.السّٰبِحٰتِ سَبْحًامیں عالمگیر ترقی کرنے کے دو اصولوں کی طرف اشارہ اس جگہ دو ضمنی باتیں بھی بیان کرنے کے قابل ہیں جو بطور قانونی سبق کے اِن آیات سے نکلتی ہیں اور وہ یہ ہیں.اوّل.اس جگہ اسلامی ترقی کے لئےوَالسّٰبِحٰتِ سَبْحًا فرمایا یعنی ابتداءمیں ہی دور دور تک اس کی اشاعت ہو جائے گی.اِس سے اس طرف اشارہ ہے کہ اسلام کی تحریک عالمگیر کشش رکھنے والی ہے کسی ایک ملک یا قوم سے اس کو وابستگی نہیں.قومی یا ملکی روایات کی زمین میں اس کی جڑیں نہیں گاڑیں گئیں بلکہ اخلاقِ انسانی اور جذباتِ انسانی کی زمین میں اس کی بنیادیں رکھی گئی ہیں اس لئے وہ جلد جلد دُور دُور پھیل جائے گا.خواہ شروع میں تھوڑے لوگ ماننے والے ہوں مگر جلد ہی سب قوموں کی توجہ کو اسلام کھینچ لے گا.جہاں اس میں اسلام کی ایک زبردست فضیلت کا اظہار ہے جس کی تفصیل کا یہ مقام نہیں وہاں اس میں سب ایسی تحریکوںکے لئے جو عالمگیر ہونا چاہتی ہوں ایک نکتہ ٔ معرفت بھی بیان کیا گیا ہے.جب تک انسان اپنے قومی تعصّب سے بالا نہیں ہو جاتا وہ کوئی عالمگیر تحریک بھی نہیں کر سکتا.مثلاً ہندوستان صرف ایک ملک ہے دنیا نہیں.مگر یہاں کے سیاسی لیڈر ابھی تک وطنی فضا بھی پیدا نہیں کر سکے کیونکہ انہوں نے اپنی تحریکوں کی جڑیں قومی دبائو کی وجہ سے یا اپنے نسبی میلانوں سے مجبور ہو
Page 148
کر ملکی نہیں بلکہ قبائلی میلانات کی زمین میں گاڑیں ہیں اس وجہ سے وہ درخت جو ان تحریکوں سے پیدا ہوتے ہیں ایک وقت تک نشوونما پا کر یا کلی طور پر یا جزوی طور پر خشک ہوناشروع ہو جاتے ہیں اور سارے ملک کو سایہ دینے والا درخت اُن سے پیدا نہیں ہوتا.اسلام نے شدیدقومی تعصبات کے زمانہ میں جب مدینہ جیسے معمولی قصبہ کے دو قبیلے اوس ؔ اور خزرجؔ بھی آپس میں لڑ رہے تھے مکّہ سے اوس و خزرج کو کھینچا یمن جو عرب میں سیاسی برتری کا مدعی تھا اسے اپنے تابع کیا یہود سے عبداللہ بن سلام اور ایران سے سلمان فارسی دوڑتے ہوئے آئے مگر یہ صرف اپنی قوموں کے نمائندے تھے بعد میں قومیں آئیں اور پروانوں کی طرح آئیں کیونکہ اسلام ایک تالاب کا پانی نہ تھا وہ بارش تھی جو ٹیلے پر برستی ہے اور وہ وہیں جمع نہیں ہو جاتی بلکہ دُور دُورپھیل جاتی ہے اس کے حامل قومی کارکن نہ تھے وہ بنی نوع انسا ن کے خادم تھے ہر اک نے سمجھا میں ہی اس دولت کا وارث نہیں دُوسرے ملک بھی اس میں حصہ دار ہیں چنانچہ وہ اس تعلیم کو لے کر دوڑاا ور سب جہان میں اس کی تعلیم پھیل گئی اگرو ہ تعلیم قومی اور ملکی روایا ت سے متاثر ہوتی یا اس کے ماننے والے مخصوص قوم و ملک کی برتری کے خواہش مند ہوتے تو یہ کبھی نہ ہوتا اب بھی جو قوم انہی مقصود حدود کے مطابق اپنی تعلیم اور اپنے اخلاق کو وسیع نہ کرے گی کبھی بھی اپنی مقصود حدود کو نہ پہنچ سکے گی.اسلامی تعلیم ہر قسم کی فطرت کے لئے دوسرا سبق اس آیت میں یہ دیا گیا ہے کہ اسلام کی تعلیم حدود کے لحاظ سے ہی وسیع نہیں بلکہ طبائع کے لحاظ سے بھی وسیع ہے اور اسی کی طرف بھی نَازِعَات اور نَاشِطَات کے جمع کے صیغوں سے اشارہ کیا گیا ہے یعنی ملائکہ کے کئی کئی طوائف اس کام میں لگے ہوئے ہیں اس کے مخاطب کسی ایک فطرت کے آدمی نہیں بلکہ ہر فطرت تک وہ پہنچتی ہے اس مضمون کی تفصیل کی بھی تفسیر حامل نہیں ہو سکتی مگر یہ موٹی موٹی باتیں ذہن میں رکھو تو یہ امر سمجھ میں آجاتا ہے کہ اسلام میں سیاسی، تمدنی، معاشرتی، تجارتی، اقتصادی سب ہی قسم کے احکام بیان ہوئے ہیں پھر آقا اور ماتحت.بیوی اور میاں.باپ اور اولاد.بھائی اور بھائی.استاد اور شاگرد.غریب اور امیر.بادشاہ اور رعایا.دوست اور دوست سب ہی کے متعلق غیر جانبدارانہ تعلیم موجود ہے اس کے علاوہ عبادت گزار.سپاہی.قاضی.جہاد کی طرف میلان رکھنے والا.انصاف کا دلدادہ.تعلیم کا شیدا.صدقہ و خیرات کا شائق اور تنظیم کا خواہش مند غرض کون سا طبعی مادہ ہے جس کے ابھارنے کی اس میں سبیل پیدا نہیں کی گئی.پس جہاں یہ کہہ کر کہ اسلام کی تبلیغ کے لئے ہر ملک اور ہر طبیعت کے مؤکل ملائکہ مقرر کئے گئے ہیں کیونکہ اس میں ہر ملک کی طرف اور ہر طبیعت کی طرف توجہ کی گئی ہے اسلام کی برتری کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہاں عالمگیر تحریکوں کو اس طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے کہ جہانگیر تحریکوں کے لئے ہر طبیعت اور ہر قوم کے لوگوں کا لحاظ رکھنا اس حد تک کہ اُن کا لحاظ قومی اور ملی کاموں میں
Page 149
روک نہ ہو ضروری ہے بلکہ ہر فرد کی مخصوص قابلیت کو ابھارنا قومی ترقی کا ایک اہم اور قیمتی جزو ہے.انہی معنوں کے رو سے یہ آیات طوائف ملائکہ کی جگہ طوائفِ مومنین کی طرف بھی اشارہ کرتی ہیں لیکن اس تشریح کی ضرورت نہیں کیونکہ اُوپر کی تشریح کے مطابق اسے خود ہی حل کیا جا سکتا ہے.سورۃ نازعات کی پہلی پانچ آیتوں کی تفسیر اس لحاظ سے کہ ان آیات میں طوائف انسانی مراد ہیں اب میں ان آیات کی ایک دوسری تشریح بیان کرتا ہوں اور یہ تشریح اس امر کو فرض کر کے ہے کہ اس جگہ طوائفِ ملائکہ مراد نہیں بلکہ طوائفِ انسانی مراد ہیں.نَزَعَ کے ایک معنے تیر اندازی کے ہیں اور نَشَطَکے معنے رسیوں سے باندھنے کے ہیں.سَبَحَ کے معنے تیرنے یا دُور دُور نکل جانے کے ہیں.سِبَاق کے معنے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کے اور غالب آجانے کے ہیں اور تدبیر امر کے معنے نظامِ حکومت کے ہاتھ میں آجانے کے ہیں.ان معنوں کے رُو سے یہ ایک پیشگوئی ہے اسلامی فتوحات کی.سورۂ نبأ میں یوم الفصل کی طرف اشارہ کیا تھا اور اُس دن کی طرف توجہ دلائی گئی تھی جب اسلام کا غلبہ ایسے رنگ میں ہو جائے گا کہ کافر کہے گا یَالَیْتَنِیْ کُنْتُ تُرَابًا کہ اُف! اسلام اس قدر غالب آ گیا کاش میں اس سے پہلے مٹی ہو چکا ہوتا.اسی مضمون کی تفصیل سورۂ نازعات میں بیان کی گئی ہیں اور بتایا گیا ہے کہ اس غلبہ کا آغاز کس طرح ہو گا اور انتہاکیا ہو گی.فرماتا ہے وَ النّٰزِعٰتِ غَرْقًا ہم مسلمانوں کے اُن گروہوں کو اپنے دعویٰ کی شہادت کے طور پر پیش کرتے ہیں جو تیر انداز ہوں گے اور ایسے تیر انداز ہوں گے کہ اِغْرَاق کی کیفیت ان کو حاصل ہوگی یعنی جب وہ اس کام میں لگیں گے تو انہیں تن بدن کا ہوش نہ رہے گا اور وہ اس کام اور مقصد کو اس انتہاء تک پہنچا دیں گے یہ صحابہؓ کے گروہ ہیں.وہ صحابہؓ جو اس سورۃ کے نزول کے وقت صرف چند آد می تھے اور ابھی وہ ایک گروہ بھی نہیں کہلا سکتے تھے اور مظالم کا شکار تھے تلوار تو الگ رہی اپنے دشمن کے سامنے ہاتھ بھی نہ اٹھا سکتے تھے.فرماتا ہے وہ غلبۂ اسلام کا دن جب کفار میں سے بعض کہیں گے کہ کاش ہم مٹی ہوتے اس طرح آئے گا کہ ہم اسلام کو ملک میں پھیلادیں گے.مختلف اقوام اس میں داخل ہو جائیں گی.لڑائی کی اجازت اُن کو مل جائے گی اور یہ اپنے جہاد کے فرض کو اس طرح ادا کریں گے کہ کسی نے اس طرح ادا نہ کیا ہو گا کیونکہ اِغْرَاق کے معنے ہیں کسی کام کو اس کی حد تک پہنچا دینا.اب دیکھو کس طرح آئندہ زمانہ نے اس پیشگوئی کو پورا کیا.اسلام مکہ سے نکل کر مدینہ پہنچا اور ایک قوم سے دو قوم بن گیا.آگے مدینہ میں دو قومیں بستی تھیں اوس اور خزرج.اور وہ بھی ایک نہ تھے دونوں میں شدید رقابت تھی اس طرح وہ دو سے تین قوم بن گیا اور جمع کے صیغہ کا اُن پر اطلاق جائز ہو گیا.چنانچہ جس دن سےمسلمانوں کو جنگ میں آنے کی اجازت ملی اُسی دن
Page 150
سے وہ تین گروہ تھے اور وہ نَازِعَات اور نَاشِطَات کہلانے کے مستحق تھے.جب یہ تین گروہ اسلام کے جھنڈے کے نیچے آگئے تو وہ وقت آگیا جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقٰتَلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوْا١ؕ وَ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرُ.ا۟لَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ اِلَّاۤ اَنْ يَّقُوْلُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ١ؕ وَ لَوْ لَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَ بِيَعٌ وَّ صَلَوٰتٌ وَّ مَسٰجِدُ يُذْكَرُ فِيْهَا اسْمُ اللّٰهِ كَثِيْرًا١ؕ وَ لَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ١ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ.اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِي الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَ اَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ١ؕ وَ لِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ (الحج :۴۰ تا ۴۲) یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں کو جن سے جنگ کی جارہی تھی لڑائی کی اجازت دی گئی ہے اور اس لئے دی گئی ہے کہ ان پر ظلم کیا گیا تھا اور اس لئے اجازت دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر قادر ہے اگر اس جنگ کے نتیجہ میں انہوں نے فنا ہوجانا ہوتا تو وہ ان کو کبھی جنگ کی اجازت نہ دیتا اس کی اجازت دینا ہی اس بات کاثبوت ہے کہ خدا ان کی مدد کا ذمہ وار ہو گیا ہے.وہ لوگ ایسے ہیں جو اپنے گھروں سے نکالے گئے بغیر اس کے کہ کوئی وجہ ہوتی.صرف اس بناء پر کہ انہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے اور اگر اللہ تعالیٰ بعض قوموں سے بعض کا شر دور نہ کرے تو یہودیوں اور عیسائیوں اور مسلمانوں سب کی عبادت گاہیں تباہ ہو جائیں جن میں خدا تعالیٰ کا بڑی کثرت سے ذکر ہوتا ہے.اور یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا جواس کے دین کی تائیدکے لئے کھڑا ہو گا اور اللہ بڑا قوی اور غالب ہے.وہ لوگ جن کو اب بادشاہت ملنے والی ہے ایسے ہیں کہ جب ہم ان کے ہاتھ میں نظامِ حکومت دیں گے تو وہ نمازوں کو قائم کریں گے اور زکوٰ ۃ دیں گے اور نیک باتوں کا حکم دیں گے اور بُری باتوں سے روکیں گے اور دُنیا میں اپنی نہیں خدا کی بادشاہت قائم کریں گے.چنانچہ بدرؔکے موقع پر یہ بات پوری ہوئی.صحابہ ؓ کو ر لڑائی کی اجازت ملی اور وہ اپنے سے تین گُنے سے بھی زیادہ دشمن کے مقابل پر جا کھڑے ہوئے اور یہ جنگ زیادہ تر تیروں کی جنگ تھی اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَارَمَیْتَ اِذْرَمَیْتَ وَلٰکِنَّ اللّٰہَ رَمَی (الانفال:۱۸)گو اس میں مٹھی بھر کنکروں کی طرف بھی اشارہ ہے مگر اس طرف بھی اشارہ ہے کہ اس مٹھی کے پھینکنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پیچھے کی طرف سے ہوا چلا دی (زرقانی مواھب اللدینیۃ للعسطلانی باب غزوۃ بدر العظمی) اور نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کے تیر نشانہ پر اور زور سے لگتے اور کفار کے ہوا کے دبائو سے یا تو رستہ میں رہ جاتے یا بے اثر ہو جاتے.اُن کے غَرْقًا ہونے کا ثبوت کہ بس ایک ہی مقصد اُن کے سامنے تھا کہ کچھ ہو.کتنا عرصہ لگے وہ جنگ کرتے ہی چلے جائیں گے پیچھے نہ ہٹیں گے کفار کے ایک سردار عمیر بن وہب کے واقعہ سے ملتا ہے.اُسے مکہ والوں نے
Page 151
جنگ بدر کے موقعہ پر مسلمانوں کا اندازہ لگانے کے لئے بھجوایا اُس نے واپس آ کر کہاکہ مسلمان تین سو یا اس کے لگ بھگ ہوں گے اور یہ اندازہ صحیح تھا مسلمانوں کی تعداد ۳۱۳ تھی.مگر اُس کے بعد اس نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم گو وہ تھوڑے ہیں مگر میرا مشورہ یہ ہے کہ اُن سے جنگ نہ کرو کیونکہ میں نےاونٹنیوںپر آدمی نہیں بلکہ موتیں سوار دیکھی ہیں (السیرۃ النبویۃ لابن ہشام ذکر غزوۃ بدرالکبریٰ ، تشاور قریش فی الرجوع عن القتال) یعنی اُن میں سےہر شخص کے چہر ہ سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ وہ لڑتے لڑتے مر جانے کے لئے آیا ہے اس لئے نہیں آیا کہ یہاں سے زندہ واپس جائے.پہلے تو کفار مکّہ اُس کی بات سے متاثر ہوئے مگر ابو جہل کی ایک تدبیر سے لڑائی شروع ہو گئی.فریضہ جنگ کو ادا کرنے میں مسلمانوں کی حیرت انگیز قربانیاں دوسری شہادت اس کی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ایک واقعہ سے ملتی ہے.بدر کی جنگ کے کچھ عرصہ بعد جب اُن کے لڑکے عبدالرحمٰن بھی مسلمان ہو کر مدینہ آگئے تو ایک دفعہ کسی مجلس میں باپ بیٹا دونوں آپس میں گفتگو کر رہے تھے اور پُرانی باتوں کا تذکرہ جاری تھا کہ باتوں باتوں میں جنگ بدر کا ذکر آگیا.عبدالرحمٰن نے کہا ابّا جان کئی دفعہ آپ لڑتے لڑتے ایسی جگہ پر پہنچے جہاں آپ میری زد میں ہوتے تھے.لیکن ہر دفعہ میں نے حملہ سے گریز کیا اور میں نے کہا کہ میں اپنے باپ کو تو نہیں مار سکتا.تب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا میری نظر تم پر نہ پڑی ورنہ اگر میری نظر پڑ جاتی تو میں نے کوئی لحاظ نہیں کرنا تھا کہ یہ میرا بیٹا ہے بلکہ میں نے اُسی وقت تم کو قتل کر دینا تھا (الروض الانف شرح ابن ہشام الجزء الثالث غزوۃ بدر فصل وذکر قول ابی بکر الصدیق ؓ لابنہ...) حالانکہ عام طور پر بیٹوں کو اپنے باپ سے جو محبت ہوتی ہے اس سے بہت زیادہ باپ کو اپنے بیٹوں سے محبت ہوتی ہے.مگر یہ اسلام کی ہی روح تھی جس نے ہر باپ اور ہربیٹے ،ہر خاوند اور ہر بیوی کو اس بات پر آمادہ کر دیا تھا کہ سچائی کے راستہ میں کوئی چیز بھی روک ہو ہم نے اس کی پروا نہیں کر نی.غرض مومنین و کفار کی شہادتوں سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ صحابہؓ کی جماعتیں وَ النّٰزِعٰتِ غَرْقًا کی مصداق تھیں پہلے وہ صلح سے رہے اور صبر دکھایا تو حد تک دکھایا اور جب نَازِعَات بنے اور تیر کمان ہاتھ میں پکڑ لئے تو غَرْقًا ہونے کا ایسا ثبوت دیا کہ جب تک تن سے جان نہیں نکل گئی کمان کو ہاتھ سے نہیں چھوڑا.اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَلی اَصْحٰبِ مُحَمَّدٍ وَّبَارِکْ وَسَلِّمْ اِنَّکَ حَمِیْدٌ مَّجِیْدٌ.کفار کے لئے اسی دنیا میں يٰلَيْتَنِيْ كُنْتُ تُرٰبًا کا نظارہ چنانچہ اس اخلاص کا نتیجہ یہ نکلا کہ يٰلَيْتَنِيْ كُنْتُ تُرٰبًا کا نظارہ کفار نے اسی دنیا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا.ابو جہل جو مکّہ کے تمام گھرانوں کا سردار اور کفار کی فوج کا کمانڈر تھا جب بد رکی جنگ کے موقعہ پر وہ فوج کی ترتیب کر رہا تھا حضرت عبدالرحمٰن بن عوف جیسا تجربہ کار
Page 152
جرنیل کہتا ہے کہ میں نے اپنے دائیں بائیں دو انصاری لڑکوں کو دیکھا جو پندرہ پندرہ سال کی عمر کے تھے میں نے اُن کو دیکھ کر کہا آج دل کی حسرتیں نکالنے کا موقعہ نہیں بدقسمتی سے میرے اردگرد ناتجربہ کار بچے اور وہ بھی انصاری بچے کھڑے ہیں جن کو جنگ سے کوئی مناسبت ہی نہیں.میں اسی ادھیڑ بُن میں تھا کہ دائیں طرف سے میرے پہلو میںکہنی لگی میں نے سمجھا کہ دائیں طرف کا بچہ کچھ کہنا چاہتا ہے اور میں نے اس کی طرف اپنا منہ موڑا.اُس نے کہا کہ چچا ذراجھک کر بات سنو میں آپ کے کان میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں تا کہ میرا ساتھی اس بات کو نہ سُن لے.وہ کہتے ہیں جب میں نے اپنا کان اُس کی طرف جھکایا تو اس نے کہا چچا وہ ابوجہل کون سا ہے جو رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم کو اس قدر دکھ دیا کرتا تھا.چچا میرا دل چاہتا ہے کہ میں اُس کو ماروں.وہ کہتے ہیں ابھی اس کی یہ بات ختم نہ ہوئی تھی کہ میرے بائیں پہلو میں کہنی لگی اور میں اپنے بائیں طرف کے بچے کی طرف جھک گیا اور اس بائیں طرف والے بچے نے بھی یہی کہا کہ چچا وہ ا بو جہل کون سا ہے جو رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم کو اتنا دکھ دیا کرتا تھا.میرا دل چاہتا ہے کہ میں آج اس کو ماروں.حضرت عبدا لرحمٰن بن عوف کہتے ہیں باوجود تجربہ کار سپاہی ہونے کے میرے دل میں یہ خیال بھی نہیں آسکتا تھا کہ ابو جہل جو فوج کا کمانڈر تھا جو تجربہ کار سپاہیوں کے حلقہ میں کھڑا تھا اس کو میں مار سکتا ہوں.میں نے انگلی اٹھائی اور ایک ہی وقت میں اُن دونوں لڑکوں کو بتا یا کہ وہ سامنے جو شخص خَود پہنے زرہ میں چھپا ہوا کھڑا ہے جس کے سامنے مضبوط اور بہادر جرنیل ننگی تلواریں اپنے ہاتھوں میں لئے کھڑے ہیں وُہ ابوجہل ہے.میرا مطلب یہ تھا کہ میںاُن کو بتائوں کہ تمہارے جیسے ناتجربہ کار بچوں کے اختیار سے یہ بات باہر ہے.مگر وہ کہتے ہیں میری وہ انگلی جو اشارہ کر رہی تھی ابھی نیچے نہیںجھکی تھی کہ جیسے باز چڑیا پر حملہ کرتا ہے اسی طرح وہ دونوں انصاری بچے کفار کی صفوں کو چیرتے ہوئے ابوجہل کی طرف دوڑنا شروع ہوئے.ابو جہل کے آگے عکرمہ اس کا بیٹا کھڑا تھا جو بڑا بہادر اور تجربہ کار جرنیل تھا مگر یہ انصاری بچے اس تیزی سے گئے کہ کسی کو وہم و گمان بھی نہ ہو سکتا تھا کہ کس مقصد کے لئے یہ آگے بڑھے ہیں اور دیکھتے دیکھتے ابو جہل پر حملہ کرنے کے لئے کفار کی صفوں کو چیرتے ہوئے عین پہر ہ داروں تک جا پہنچے.ننگی تلواریں اپنے ہاتھ میں لئے جو پہرے دار کھڑے تھے وہ وقت پر اپنی تلواریں بھی نیچے نہ لا سکے صرف ایک پہرے دار کی تلوار نیچے جھک سکی اور ایک انصاری لڑکے کا بازو کٹ گیا مگر جن کو جان دینا آسان معلوم ہوتا تھا ان کے لئے بازو کا کٹنا کیا روک بن سکتا تھا.جس طرح پہاڑ پر سے پتھر گرتا ہے اسی طرح وہ دونوں لڑکے پہرہ داروں پر دبائو ڈالتے ہوئے ابوجہل پر جا گرے اور جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی کفار کے کمانڈر کو جا گرایا.حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کہتے ہیں کہ میں جنگ کے آخری وقت میں وہاں پہنچا جہاں ابو جہل جان کندنی کی
Page 153
حالت میں پڑا ہوا تھا میں نے کہا سنائو کیا حال ہے اُس نے کہا مر رہا ہوں پر حسرت سے مر رہا ہوں کیونکہ مرنا تو کوئی بڑی بات نہیں لیکن افسوس یہ ہے کہ دل کی حسرت نکالنے سے پہلے انصار کے دو چھوکروں نے مجھے مار گرایا.مکہ کے لوگ انصار کو بہت حقیر سمجھا کرتے تھے اسی لئے اُس نے افسوس کے ساتھ اس کا ذکر کیا اور کہا کہ یہی حسرت ہے جو اپنے دل میں لئے مر رہا ہوں کہ انصار کے دو چھوکروں نے مجھے مار ڈالا.پھر وہ ان سے کہنے لگا میں اس قدر شدیدتکلیف میں ہوں کہ تم مجھ پر احسان کرو گے اگر تلوار کے ایک وار سے میرا خاتمہ کر دو مگر دیکھنا میری گردن ذرالمبی کاٹنا کہ جرنیل کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کی گردن لمبی کاٹی جاتی ہے.حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے اس کی یہ بات تو مان لی کہ مجھے قتل کر دو اور اس دکھ سے بچا لو مگر انہوں نے ٹھوڑی کے پاس سے اُس کی گردن کو کاٹا.گویا مرتے وقت اس کی یہ حسرت بھی پوری نہ ہوئی کہ اس کی گردن لمبی کاٹی جائے (سیرت النبویّۃ لابن ہشام زیر عنوان ذکر رویا عاتکۃ بنت عبد المطلب عود الی مقتل ابی جھل)دیکھو کس واضح طور پر یہ پیشگوئی پوری ہوئی کہ وَ يَقُوْلُ الْكٰفِرُ يٰلَيْتَنِيْ كُنْتُ تُرٰبًا.اَلْ کو ہم معہود ذہنی کے طور پر بھی لے سکتے ہیں اور کمال کے معنوں میں بھی لے سکتے ہیں اس صورت میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وَیَقُوْلُ الْکَافِرُ یَالَیْتَنِیْ کُنْتُ تُرَابًا.میں الْکَافِرُ سے مراد کفرکا مجسمہ یا کافروں کا سردار ابوجہل تھا.اور اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ اُس دن یہ کافر کہے گا اے کاش میں اس سے پہلے مٹی ہو چکا ہوتا.چنانچہ واقعات پر غور کرو اور سوچو کیا ابو جہل نے اس دن نہیں کہا کہ اے کاش میں اس سے پہلے مٹی ہو چکا ہوتا.اُس نے اپنی ذلّت کا نظارہ اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اس طرح وہ پیشگوئی بڑی شان کے ساتھ پوری ہو گئی جو سو رۂ نبأ میں بیان کی گئی تھی.النّٰشِطٰتِ نَشْطًامیں مسلمانوں کے کفار پر غالب آنے کی پیشگوئی اس کے بعدکی آیت ہے وَالنّٰشِطٰتِ نَشْطًا اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس جنگ کا نتیجہ یہ نہ ہو گا کہ مسلمان مارے جائیں.پہلی آیت نے شکست کا سوال حل کر دیا تھا اور بتا دیا تھا کہ اُن کے سامنےشکست وفتح کا کوئی سوال نہیں ہو گا اُن کے سامنے سوال صرف یہ ہو گا کہ اسلام پر پروانہ وار فدا ہو جائیں.اب اِس آیت میں دوسرے سوال کا جواب دیا گیا ہے کہ کیا اسطرح اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنے کے نتیجہ میں وہ تباہ ہو جائیں گے فرماتا ہے نہیں ایسا نہ ہو گا اس جنگ کے نتیجہ میں مسلمان مارے نہیں جائیں گے بلکہ جیتیں گے اور رسیوں سے اپنے دشمنوں کو باندھیں گے اور قید کریں گے چنانچہ بدر کی جنگ میں بہت سے قیدی ہاتھ آئے اور رسیوں سے ہی باندھے گئے.(الزرقانی غزوۃ بدر) السّٰبِحٰتِ سَبْحًامیں مسلمانوں کے مدینہ سے دور جا کر جنگیں کرنے کی پیشگوئی وَ السّٰبِحٰتِ سَبْحًاۙ
Page 154
اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ وہ فنونِ جنگ کے بڑے ماہر اور تیراک ہو جائیں گے.کیونکہ جو شخـص کسی فن میں ماہر ہو جاتا ہے اُس کے متعلق یہی کہتے ہیں کہ وہ اس فن میں تیرتا ہے یعنی سہولت سے اپنے فرائض کو بجا لاتا ہے.یہ نظارہ بھی صحابہؓ نے دکھایا وہ فنون جنگ کے ایسے ماہر ہو گئے کہ بعد میں جب قیصرو کسریٰ کی تجربہ کار اور تنخواہ دار رفوجوں سے اُن کا مقابلہ ہوا تب بھی یہ لوگ اُن پر غالب رہے.دوسرے معنے اس کے یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ اُن کی جنگیں مدینہ سے دُور دُور چلی جائیں گی اور جس طرح تیرنے والا کنارہ سےدُور سے چلا جاتا ہے اسی طرح مدینہ سے شروع ہو کر دشمن کو دباتے ہوئے وہ دُور دُور تک نکل جائیں گے چنانچہ جنگ کے بعد جنگ ہوئی اور آخر اطرافِ عرب تک جنگیں جا پہنچیں.السّٰبِقٰتِ سَبْقًامیں مسلمانوں کی پے در پے جنگیں کرنے کی پیشگوئی پھر فرمایا فَالسّٰبِقٰتِ سَبْقًا ہم اُن گروہ مسلمین کو شہادت کے طور پر پیش کرتے ہیں جو ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کریں گے.جب جنگ دُور دُور تک پھیل جاتی ہے اور ایک کے بعد دُوسری اور دوسری کے بعد تیسری جنگ شروع ہو کر اُس کا سلسلہ لمبا ہوتا چلا جاتا ہے تو عام طور پر قومیں تھک جاتی ہیں مگر فرماتا ہے کہ مسلمانوں میں ایسے آد می موجود ہوں گے جو اپنے اندر یہ روح رکھتے ہیں ہوں گے کہ جنگ کی لمبائی اور اس کی وسعت اُن کو تھکائے گی نہیں.اُن کے حوصلے بڑھتے جائیں گے اور ان کے ایمان زیادہ ہی ہوتے جائیںگے یہاں تک کہ وہ جان دینے کو ایک کھیل سمجھنے لگیں گے اور ایک دوسرے سے اس میدان میں بڑھنے کی کوشش کریں گے جس طرح فٹ بال اور کرکٹ کی ٹیموں میں کھلاڑی ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اسی طرح وہ جان دینے میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کریں گے اور آخر فَالْمُدَبِّرٰتِ۠ اَمْرًا کا زمانہ آجائے گا اور زمامِ حکومت اُن کے ہاتھ میں آجائے گی اور جن قوموں میں اُوپر والے اخلاق پیدا ہو جائیں حکومت اُن ہی کے ہاتھ میں آیا کرتی ہے.حکومت کو اُن کے ہاتھوں میں آنے سے کوئی روک نہیں سکتا.دُشمن کے مقابلہ میں اِغْرَاق کی کیفیت کا پیدا ہو جانا اور اس قدر اپنے اندر انہماک پیداکر لینا کہ اُس فن میں ایک سہولت اور لذت محسوس ہونے لگے اور پھر قومی قربانی کے مقابلہ میں آپس میں مسابقت کی روح کا پیدا ہو جانا یہ قوم کو غالب بنادیا کرتا ہے.اور یہی پیشگوئی مسلمانوں کے متعلق ان آیات میں کی گئی ہے چنانچہ ایسا ہی نظارہ صحابہؓ نے بعد میں دکھایا.سورۃ نازعات کی پہلی آیات کے تیسرے معنے تیسرا سلسلۂ مضامین ایک اور بھی اس سے نکلتا ہے اور وہ روحانی قابلیت کا ہے نَزَعَ یَنْزِعُ نُزُوْعًا عَنْ کَذَا کے معنے ہوتے ہیں کَفَّ عَنْہُ اس سے رُک گیا اور نَشَطَ
Page 155
الدَّلْوَمِنَ الْبِئْرِ کے معنے ہیں نَزَعَھَا وَانْتَشَلَھَابِلَا بَکْرَۃٍ یعنی بغیر چرخی کے ہاتھ سے پانی نکالا جو مشقت کا کام ہوتا ہے.اس سوال کا جواب کہ کمزور مسلمان کیونکر دنیا پر غالب آئیں گے جیسا کہ بیان کیا جاچکا ہے قرآن کریم نے غلبۂ اسلام اور قیامت دونوں کو ملا کر بیان کیا ہے اور بتا یا ہے کہ تم اسلام کے غلبہ اور قیامت دونوں کے منکر ہو مگر یہ دونوں باتیں ہو کر رہیں گی اور ان میں سے ایک چیز دوسری کا ثبوت ہوگی یہی مضمون سورۂ نبأ میں تھا.اب اللہ تعالیٰ نے کفار کے ایک اعتراض کے پہلو کو لیا ہے.انسانی فطرت میں یہ اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ مان لیا خدا ایسا کر دے گا مگر دنیا میں خدا جو کچھ کرتا ہے اس کے کچھ آثار اور شواہد بھی پہلے سے ظاہر ہونے شروع ہو جاتے ہیں خدا تعالیٰ بچہ پیدا کرتا ہے اور اس سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا مگر اس کے لئے خدا تعالیٰ نے مرد اور عورت دونوں میں بچہ کی قابلیت رکھی ہے.جب ایک مرد اور عورت کا آپس میں نکاح ہو جاتا ہے تو ہمیں نظر آجاتا ہے کہ اب دونوں میں ہیجان پیدا ہونا شروع ہو گیا ہے.پھر میاں بیوی اکٹھے رہتے ہیں تو ہمیں اور زیادہ یقین پیداہو جاتا ہے کہ اب بچہ پیدا ہونے کے آثار شروع ہو گئے ہیں.چند دنوں کے بعد اُن آثار کاظاہر میں بھی علم ہو جاتا ہے اور ہر شخص کہنے لگ جاتا ہے کہ اب اُن کے ہاں بچہ پیدا ہو جائے گا.گو بچہ پیدا ہونے میں ابھی دیر ہوتی ہے مگر بہرحال انسان سمجھ لیتا ہے کہ چند ماہ کے بعد بچہ ضرور پیدا ہو جائے گا کیونکہ آثار نظر آنے لگ گئے ہیں.یا ایک لڑکا علم حاصل کرنے کے لئے کالج میں جاتا ہے تو ہم جانتے ہیں یہ ایک دن پڑھ جائے گا یا اگر کوئی شخص کہے فلاں آدمی نے محل بنانا ہے اور ہمیں یہ بھی نظر آتا ہو کہ اس کے پاس مال ہے دولت ہے طاقت ہے تو گو ہمیں ظاہر میں محل کے آثار نظر نہ آتے ہوں مگر ہم سمجھ لیتے ہیں کہ چونکہ محل کے سامان موجود ہیں.ارادہ موجود ہے.بنانے والے موجود ہیں.اس لئے ایک دن محل بھی بن جائے گا.تو دنیا میں کسی چیز کے متعلق لوگوں کو اُس وقت تک یقین نہیں آتا جب تک اُس کے کچھ نہ کچھ آثار وہ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھنے لگ جائیں.اسی اصول کے مطابق کفار مسلمانوں پر اعتراض کرتے تھے کہ تم کہتے ہو قیامت آئے گی اور جب تم سے پوچھا جاتا ہے کہ قیامت کا ثبوت کیاہے تو تم کہتے ہو اس کا ثبوت یہ ہے کہ اسلام غالب آجائے گا اور کفر مٹ جائے گا اور اسلام کا غلبہ اس بات کی دلیل ہو گا کہ جو دوسری بات بتائی گئی ہے وہ بھی ایک دن پوری ہو جائے گی مگر یہ غلبۂ اسلام جسے قیامت کے ثبوت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے خود ابھی ثبوت کا محتاج ہے اور ہمیں اُس کے کوئی آثار ظاہر میں نظر نہیں آتے.آٹھ دس آدمی ہیں جو ابھی ایمان لائے ہیں مگر اُن میں دنیا پر غالب آنے کی کوئی روح نظر نہیں آتی.انسان دنیا پر غالب آتا ہے اپنے علم کے زور سے مگر ان میں کون سا عالم
Page 156
ہے.اُن کی مراد عالمِ روحانی سے نہیں تھی بلکہ کہانت وغیرہ کی طرف ان کا اشارہ تھا کہ اس قسم کے علوم کا انہیں کچھ پتہ نہیں.اسی طرح دنیا پر صنعت کے ذریعہ سے غلبہ حاصل ہوتا ہے مگر ان میں کوئی ایسے صناع بھی نہیں ہیں جن کو دیکھ کر یہ فیصلہ کیا جا سکے کہ دنیا کو یہ لوگ مغلوب کر لیں گے.اتنے بڑے جرنیل بھی نہیں ہیں کہ ان کے متعلق خیال کیا جاسکے کہ یہ دنیا کو فتح کر لیں گے.اتنا بڑا رعب اور دبدبا رکھنے والے بھی یہ لوگ نہیں ہیں کہ دنیا مرعوب ہو کر ان کے پیچھے چل پڑے گی.چند غریب آدمی ہیں جو ایمان لائے ہیں اور اُن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ ساری دُنیا پر غالب آجائیں گے حالانکہ نہ اُن میں کوئی قابلیت پائی جاتی ہے نہ اُن کے اندر ذاتی جوہر ایسے نظر آتے ہیں کہ گو آج یہ قابل نہیں ہیں مگر کچھ عرصہ کے بعد اپنی قابلیت کا سکّہ بٹھا لیں گے.صرف نماز پڑھ لینا یا کلمہ پڑھ لینا اس بات کی کوئی دلیل نہیں کہ یہ دنیا کو بھی مغلوب کر لیں گے.دنیا پر غلبہ حاصل کرنے کے لئے مخصوص قابلیتوں کا پایا جانا ضروری ہے اور وہ قابلیتیں ہمیں اُن میں دکھائی نہیں دیتیں بلکہ اُن قابلیتوں کے آثار بھی نظر نہیں آتے.گویا نہ بالفعل انہیں یہ کمالات حاصل ہیںاور نہ بالقوۃ انہیں یہ کمالات حاصل ہیں.اگر ایک کارخانہ قائم ہو رہا ہو تو اس کے متعلق امید کی جا سکتی ہے کہ اگر آج نہیں تو کل اس کارخانہ کے ذریعہ لاکھوں روپے آجائیں گے مگر یہ تو وہ لوگ ہیں کہ نہ بالفعل اُنہیں کوئی کمال حاصل ہے اور نہ بالقوّۃ انہیں کوئی کمال حاصل ہے اور جب حالت یہ ہے تو اس قسم کے لوگوں کے ذریعہ کسی آئندہ زمانہ میں ظاہر ہونے والے ایک موہوم غلبہ کو قیامت کے وجود کی دلیل کس طرح قرار دیا جا سکتا ہے؟ یہ اعتراض ہے جو سورۂ نبأ کے مضامین پر پیدا ہوتا تھا اور سورۂ نازعات میں اسی کا جواب دیا گیا ہے.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَ النّٰزِعٰتِ غَرْقًا آج مومن تم کو ذلیل نظر آتے ہیں اُن میں کوئی لیاقت نہیں.یہ اپنی قوم کے سب سے کم تعلیم یافتہ سب سے کم تجربہ کار.اور سب سے کم فنون کے جاننے والے ہیں ہر پیشہ اور علم میں پیچھے ہیں.تم ان کو ذلیل سمجھتے ہو.ناکارہ خیال کرتے ہو اور سمجھتے ہو کہ یہ کہاں جہاں داری اور سیادت کے قابل ہو سکتے ہیں لیکن یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر وہ قابلیتیں پیدا کر دی ہیں اور پیدا کر دے گا جن سے انسانوں کو سیادت اور کامیابی حاصل ہوا کرتی ہے اور یہ اپنے عمل سے وہ سب باتیں دکھا دیں گے.چنانچہ فرماتا ہے یہ تم کو بے کار وجود نظر آتے ہیں لیکن ہم شہادت کے طور پر پانچ صفات پیش کرتے ہیں جن کے متعلق تم دیکھو گے کہ وہ آہستہ آہستہ مسلمانوں میں پیدا ہوتی چلی جائیں گی اور جس قوم میں یہ پانچ صفات پیدا ہو جائیں وہ کبھی ہار نہیں سکتی.تمہارا بڑا اعتراض یہی ہے کہ یہ لوگ علم میں ،دولت میں، قوت میں،لڑائی کے فنون اور تجربہ وغیرہ میں بہت پیچھے ہیں بلکہ یہ چیزیں ان کو حاصل ہی نہیں حالانکہ علم اور دولت اور قوت اور فنون وغیرہ آسمان سے گرا نہیں کرتے اور نہ یہ چیزیں ایسی ہیں جو دنیا پر یقینی
Page 157
طور پر غلبہ حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں.سب میں سے اعلیٰ اور فائق بننے کے لئے مندرجہ ذیل قابلیتوں کا ہونا ضروری ہے اور اگر تم غور کرو تو تمہیں معلوم ہو گا کہ ان کے مسلمان ہوتے ہی یہ قابلیتیں پیدا ہو چکی ہیں اوراب روز بروز بڑھتی چلی جارہی ہیں اور اسی میں ان کی کامیابی کا راز ہے چنانچہ فرماتا ہے وَ النّٰزِعٰتِ غَرْقًا.نَزَعَ کے دو معنے ہو سکتے ہیں.اوّلؔ کَفَّ عَنْہُ اُس سے رُک گیا اور دوسرےؔ یہ معنے بھی ہوتے ہیں کہ وہ کسی چیز کا مشتاق ہوا.چنانچہ لغت میں لکھا ہے نَزَعَ نِزَاعًا اِلَی الشَّیءِ ذَھَبَ اِلَیْہِ یعنی نَزَعَ اِلَی الشَّیءِ کے معنے ہوتے ہیںاُس چیز کی خواہش دل میں پیدا ہوئی اور جب نَزَعَ اِلٰی اَھْلِہٖ کہیں تو اس کے معنے ہوں گے اِشْتَاقَ اس کے دل میںاپنے اہل سے ملنے کا اشتیاق پیدا ہوا یا اس کے دل میں اپنے اہل کی طرف رغبت پیدا ہوئی (اقرب) ان دو معنوں کو ملحوظ کرتے ہوئے اگر غور کیا جائے تو معلوم ہو گا کہ ترقی کے لئے مندرجہ ذیل قابلیتوں کی ضرورت ہوا کرتی ہے.اوّلؔ ترقی کرنے والی قوم کے اندرمادہ صبر کا پایا جانا نہایت ضروری ہے یعنی اُس میں یہ قابلیت ہونی چاہیے کہ اُسے جس بات سے بھی روکا جائے رُک جائے تاکہ جب بھی بدیوں کے مواقع آئیں خرابیوں اور تباہیوں کے اوقات آئیں وہ اپنے نفس کو روک لے اور اُن بدیوں میں ملوّث ہونے سے اپنے آپ کو بچا لے یہی وہ خوبی ہوتی ہے جس کو پیدا کرنے کی وجہ سے ایک قوم جیت جاتی ہے اور دوسری قوم اس سے محروم ہونے کی وجہ سے شکست کھا جاتی ہے.ورنہ جہاں تک آنکھ، کان، دل اور دماغ وغیرہ کا سوال ہے وہ سب میں یکساں ہوتے ہیں فرق صرف یہ ہوتاہے کہ بعض لوگ اپنے آپ کو موقعہ پڑنے پر بُری باتوںسے روک نہیں سکتے اور بعض روک لیتے ہیں.روکنے والے جیت جاتے ہیں اور دوسرے لوگ ہار جاتے ہیں.دوسریؔ چیز جس کا ترقی کرنے والی قوم کے اندر پایا جانا نہایت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی اچھی چیز اس کے سامنے آئے اُس کے دل میں یہ شدید شوق پیدا ہو جائے کہ کسی طرح میں اس چیز کو حاصل کر لوں گویا صفتِ صبر ؔاور صفتِ اشتیاقِ شدیدیا رغبتِ شدید یہ دو خوبیاں جس قوم کے اندر پائی جائیں وہ یقیناً دنیا پر غالب آجاتی ہے.اور یہی دو چیزیں ہیں جن پر ترقیات کا مدار ہے.ایک بڑا ڈاکٹر، ایک بڑا انجینئر یا ایک بڑا سیاستدان کیوں مشہور ہوتا ہے؟ اِسی لئے کہ اس ڈاکٹر کو اپنے ڈاکٹری کے فن میں اشتیاق ہوتا ہے.اس انجینئر کو اپنے انجینئرنگ کے کام کی طرف رغبت ہوتی ہے اور وہ سیاستدان اپنے ملک کی سیاسی ترقی کی تدابیر میں منہمک رہتا ہے.گاندھی جی کو ہی دیکھ لو کس طرح دن رات ملکی خدمت میں مصروف رہتے ہیں.اُن میں اور دوسرے لوگوں میں کیا فرق ہے یہی کہ گاندھی جی اس کام میں تن من سے لگ گئے اور دوسروں نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ کی.ورنہ جہاں تک آنکھ،
Page 158
کان، ناک، اور مُنہ وغیرہ کا سوال ہے جس طرح دوسروں کی آنکھیں ہیں اسی طرح گاندھی جی کی آنکھیں ہیں جس طرح دوسروں کے کان ناک اور مُنہ ہیں اِسی طرح اُن کے ہیں فرق صرف یہ ہے کہ اور لوگ تو جوئے بازی کرتے رہے یا سینما اور میوزک وغیرہ میں مشغول رہے اور وہ اس کام میں لگے رہے اگر وہ بھی اسی کام میں لگ جاتے تو آج وہ بھی بڑے بڑےکام کرنے والے سمجھے جاتے.یا ایک ڈاکٹر سے مریض کیوں اچھے ہوتے ہیں اور دوسرے سے کیوںاچھے نہیں ہوتے؟ اسی لئے کہ ایک شخص نے ڈاکٹری کے مطالعہ میں اور معالجہ میں انہماک پیدا کر لیا اور اس فن کے متعلق اُس نے رغبت اور اشتیاق کا اظہار کیا اور دوسرے نے رغبت سے کام نہ لیا.تو ترقی کرنے کے لئے دو قابلیتوں کا پایا جانا نہایت ضروری ہوتا ہے اوّلؔ یہ کہ جب کسی بُری بات سے اُسے روکا جائے تو وہ رُک جائے دوسرےؔ یہ کہ جس قدر مفید اور کارآمد چیزیں ہوں اُن کے حصول کی اُس کے دل میں شدید رغبت پائی جاتی ہو.وَ النّٰزِعٰتِ غَرْقًا کہہ کر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی انہی خوبیوں کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جتنی چیزیں انسانی ترقی میں حائل ہو سکتی ہیں اُن سب سے یہ لوگ بچتے ہیں.تم میں اور ان میں اگر کوئی فرق ہے تو یہ ہے کہ تم بعض چیزوں کے متعلق سمجھتے ہو کہ وہ بُری ہیں مگر پھر بھی اُن سے بچتے نہیں.لیکن مسلمانوں کو جس چیز کے متعلق یہ علم ہو جائے کہ وہ بُری ہے اُس کے قریب بھی وہ نہیں پھٹکتے.اس ایک بات سے ہی اندازہ لگا لو کہ ترقی کون کر سکتا ہے تم ترقی کر سکتے ہو یا مسلمان ترقی کر سکتے ہیں.تمہاری حالت تو یہ ہے کہ تم مانتے ہو شراب بُری چیز ہے.تم مانتے ہو جوا بُری چیز ہے مگر پھر نہ تم شراب سے بچتے ہو نہ جوئے سے رُکتے ہو مگر مسلمان چونکہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ بُری چیزیں ہیں اس لئے نہ وہ شراب کے قریب جاتے ہیں نہ وہ جوئے کے قریب جاتے ہیں.یہ علامت ہے اِس بات کی کہ مسلمانوں کے اندر بڑھنے اور ترقی کرنے کا مادہ پایا جاتا ہے.مگر تمہارے اندر وہ مادہ نہیں پایا جاتا.تم بھی کہتے ہو کہ سچ بڑی اچھی چیز ہے اور مسلمان بھی کہتے ہیں کہ سچ بڑی اچھی چیز ہے مگر تم سب جھوٹ بولتے ہو اور مسلمان سب سچ بولتے ہیں.تم کہتے ہو کہ انسان کو وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے مگر باوجود یہ تسلیم کرنے کے کہ وقت ضائع کرنا بُری بات ہے تم اپنے وقت کو ضائع کر دیتے ہو.تم مانتے ہو کہ دوسروں پر ظلم نہیں کرنا چاہیے مگر پھر تمہاری یہ حالت ہے کہ تم دن رات ظلم سے کام لیتے رہتے ہو.تم مانتے ہو کہ امانت بڑی اچھی چیز ہے مگر تمہاری عملی حالت یہ ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی شخص امانتًا روپیہ رکھواتا ہے تو تم کھا جاتے ہو.اب بتائو جب تم اپنے نفوس کو بُری باتوں سے نہیں روک سکتے اور مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ وہ ہر بُری بات سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں تو تم کس طرح کہہ سکتے ہو کہ مسلمانوں میں ترقی کرنے کی قابلیت نہیں ہے.
Page 159
نَزَعَ کے دوسرے معنے رغبت کے ہیںچنانچہ نَزَعَ اِلٰی الشَّیْءِ کے معنے ہوتے ہیں اِشْتَھَاہُ اس چیز کی خواہش کی اور نَزَعَ اِلیٰ اَھْلِہٖ کے معنے ہوتے ہیں اِشْتَاقَ اُسے اپنے اہل سے ملنے کا اشتیاق پیدا ہوا.گویا اس میں صرف رغبت کے معنی ہی نہیں پائے جاتے بلکہ اس رغبت کے معنے پائے جاتے ہیں جو انسان کو اپنے اہل کے متعلق ہوتی ہے اور یہ ہر شخص جانتا ہے کہ اہل کی طرف رغبت عام رغبت سے زیادہ ہوتی ہے.ایک واقف سے ملنے کی خواہش اور قسم کی ہو گی لیکن ایک بچہ جب اپنی ماں سے ملتا ہے یا ماں اپنے بچہ سے ملتی ہے تو وہ خواہش اور وہ رغبت بہت زیادہ ہوتی ہے تو وَالنَّازِعَاتِ کہہ کر اس امر کی طرف اشارہ کیا کہ گو تم میں سے بھی بعض کو نیکی کے حصول کا معمولی اشتیاق ہے لیکن مسلمان ایسے ہیں کہ جب انہیں نیک باتوں کا علم ہوتا ہے تو وہ ان کی طرف اس رغبت اور شوق سے دوڑتے ہیں جس رغبت اور شوق سے ایک بچہ اپنی ماں کی طرف جاتا ہے گویا دونوں قسم کے کمالات اُن میں نظر آتے ہیں.غرض پہلا قدم قومی ترقی کے لئے یہ ہوتا ہے کہ قوم اُن اعمال سے بچتی ہے جو ترقی میں روک ہوتے ہیں مثلاً سُستی ہے، جہالت ہے، غفلت ہے، ضد ہے، نافرمانی ہے، ظلم ہے، لڑائی جھگڑا ہے، بد سلوکی ہے، تلخی ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے، خیانت ہے، فسق وفجور ہے یا اسی طرح کی اور خرابیاں ہیں.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ لوگ وَ النّٰزِعٰتِ غَرْقًا ہیں کہ اپنے نفوس کو ایسی تمام باتوں سے روکتے ہیں جن سے رُکنا چاہیے اور ان میں یہ مادہ پایا جاتا ہے کہ جب انہیں کہا جاتا ہے فلاں بات بُری ہے اس سے بچو تو یہ فوراً اس سے رُک جاتے ہیں اور اس حد تک اپنے نفوس کو روکتے ہیں کہ غَرْقًا ہو جاتے ہیں یعنی اپنے نفوس پر غالب آجاتے ہیں مگر تمہاری یہ حالت ہے کہ تم مانتے ہو کہ فلاں فلاں باتیں بُری ہیں مگر تم ان سے بچتے نہیں.پھر یہ صرف اپنے نفوس پر ہی غالب نہیں آتے بلکہ دوسروں کی بھی اصلاح کرتے ہیں گویا ان میں خالی اپنے نفس کو روکنے کا ہی مادہ نہیں بلکہ دوسروں کی اصلاح کا مادہ بھی اُن کے اندر پایا جاتا ہے.چنانچہ اِغْرَاق کے ایک معنے یہ بھی ہیں کہ لوگ ایک شخص پر حملہ آور ہوئے اور اُسے مغلوب کر لیا گویا جب وہ اپنے کسی ساتھی میں کوئی عیب دیکھتے ہیں تو وہ صرف اس بات پر راضی نہیں ہو جاتے کہ ہم نے اپنے آپ کو اس بدی سے روکا ہوا ہے بلکہ وہ سارے اکٹھے ہو کر اس پر حملہ آور ہو جاتے اور پھر اُسے مغلوب کر لیتے ہیں یعنی یا تو وہ اُس کا عیب دُور کر دیتے ہیں اور اُسے نیک بنا لیتے ہیں اور یا پھر وہ اُس کو اپنی قوم میں سے باہر نکال دیتے ہیں.بدی کا وجود وہ اپنے اندر برداشت نہیں کر سکتے مگر یہ اوپر کا درجہ ہے پہلا درجہ یہی ہے کہ جتنی چیزیں انسان کی ترقی میں روک بننے والی ہیں وہ اُن سب سے بچتے ہیں اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ وہ بدی کو اپنی قوم میں دیکھ ہی نہیں سکتے.جہاں بدی اُن کو نظر آتی ہے فوراً اس پر حملہ کر دیتے ہیں اور بدی کرنے والے کو مغلوب کر لیتے ہیں یعنی یا تو
Page 160
اُسے باہر نکال دیں گے یا اسے جیت لیں گے اور اس کی اصلاح کر لیں گے.بہرحال وہ اُس شکل میں اس کو نہیں رہنے دیں گے جس شکل میں وہ پہلے دکھائی دیتا تھا.یہ دو قابلیتیں ہیں جو قوم کو ترقی کی طرف لے جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ دونوں قابلیتیں مسلمانوں میں پائی جاتی ہیں.پس وَ النّٰزِعٰتِ غَرْقًا کے یہ معنے ہوئے کہ وہ رُوحیں جو رکنے والی ہیں بُری باتوں سے اور بد روحیں جو اُن میںآجائیں اُن کو دبا لینے والی ہیں.وَ النّٰزِعٰتِ کے دوسرے معنے جیسا کہ بتا یا جا چکا ہے اشتیاق کے ہوتے ہیں اس لحاظ سے وَ النّٰزِعٰتِ غَرْقًا کے یہ معنے ہوں گے کہ وہ نیکیوں کی طرف اس طرح رغبت کرتے ہیں جیسے انسان اپنے اہل وعیال کی طرف رغبت کرتا ہے گویا وہ صرف بدیوں سے ہی نہیں رُکتے بلکہ اُن کے اندر امانت اور انصاف اور رحم اور خوش خلقی اور محنت اور علم اور غرباء پروری اور اقرار احسان اور جرأت اور سخاوت اور ہمسایہ کی خبر گیری.مسافروں کا خیال.یتیموں کا خیال اور بیوائوں کا خیال.صفائی کا خیال.عفّت اورایسی ہی سب نیکیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور وہ نہ صرف ان کے حصول کی کوشش کرتے ہیں بلکہ بعض کو یہ نیکیاں ایسی پیاری لگتی ہیں جیسے بچہ کو اپنی ماں سے یا ماں کو اپنے بچہ سے پیار ہوتا ہے.وَ النّٰشِطٰتِ نَشْطًا پھر فرماتا ہے ان نیکیوں کے حصول میں عاداتِ قومی کی وجہ سے انہیں محنت تو کرنی پڑتی ہے مگر وہ محنت کر کے یہ کام کرتے چلے جاتے ہیں اور اس کام میں جو صعوبتیں آئیں اُن سب کو برداشت کرتے ہیں.نَشَطَ کے ایک معنے ڈول کو بغیر چرخی کے نکالنے کے ہوتے ہیں گویا محنت اور مشقت کرنا اس کے مفہوم میں شامل ہے کیونکہ چرخی ہو تو پانی آسانی سے نکل آتا ہے اور اگر چرخی نہ ہو تو بہت زور لگانا پڑتا ہے پس عربی میں یہ محاورہ ہے کہ جب کسی کے متعلق اس امر کا اظہار کرنا ہو کہ اس نے بڑی محنت اور مشقت سے کام لیا تو کہتے ہیں اِنْتَشَلَھَا بِلَا بَکْرَۃٍ اس نے پانی بغیر چرخی کے نکالا پس وَ النّٰشِطٰتِ نَشْطًا میں صحابہؓ کی یہ خوبی بیان فرمائی کہ اُن کو نیکیوں میں ترقی کرنے کا اس قدر خیال ہے کہ اس راستہ میں انہیں کوئی بھی قربانی کرنی پڑے وہ اس سے دریغ نہیں کرتے بعض لوگوں کو نیکیوں سے رغبت بھی ہوتی ہے مگر جب کام کا وقت آئے تو اُن کا دل ڈر جاتا ہے اور وہ نیکی میں حصہ نہیں لے سکتے کیونکہ انہیں قربانی سے کام لینا پڑتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر نہ صرف یہ خوبی پائی جاتی ہے کہ انہیں نیکیوں کے حصول کا شوق ہے بلکہ اس کے ساتھ ہی یہ دوسری خوبی بھی اُن کے اندر پائی جاتی ہے کہ وہ نَاشِطَات ہیں یعنی ہر قسم کی محنت برداشت کرنے کے لئے تیار رہتے ہیں اُن کا کوئی ساتھی نہیں ہوتا.کوئی مددگار نہیں ہوتا.کوئی نیکیوں پر اکسانے والا نہیں ہوتا.کوئی پیٹھ ٹھونکنے والا اور قومی خدمات پر شاباش کہنے والا نہیں ہوتا.مگر پھر
Page 161
بھی وہ قومی خدمت کرتےچلے جاتے ہیں اور اس سے رکتے نہیں ہیں.وَ السّٰبِحٰتِ سَبْحًا یہ لازمی بات ہے کہ جو شخص محنت سے کام لیتا ہے وہ آخر فن کا ماہر ہو جاتا ہے اور جب کوئی شخص فن کا ماہر ہو جائے تو اس کے لئے کام میں سہولت پیدا ہو جاتی ہے.وہی کام جو ایک پیشہ ور لوہار کرتا ہے اگر ہمیں اس کی جگہ کرنا پڑے تو ہم بڑی محنت سے آہستہ آہستہ اس کام کو کر سکیں گے اور پھر بھی وہ کام خراب ہو جائے گا.مجھے یاد ہے بچپن میں ایک دفعہ بڑھئی ہمارے گھر میں کام کر رہے تھے مجھے ان کا کام بڑا پسند آیا اور میں نے سمجھا کہ یہ معمولی بات ہے اس کام کو تو میں بھی کر لوں گا.میری عُمر اس وقت نو دس سال کی تھی جب وہ کھانا کھانے چلے گئے تو میں نے تیشہ اٹھایا اور ایک لکڑی کو چھیلنے کے لئے اُس پر مارا مگر وہ بجائے لکڑی پر پڑنے کےسیدھا میرے ہاتھ کے انگوٹھے پر لگا جس سے گہرا زخم ہو گیا اور اس کا نشان آج تک موجود ہے دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ بڑھئی جو کچھ کر رہا ہے معمولی بات ہے اور اس طرح میں بھی کر سکتا ہوں مگر جب کام کا وقت آتا ہے تب معلوم ہوتا ہے کہ یہ کام کتنا مشکل ہے.مگر بڑھیوں کو اس کام کے کرتے وقت کوئی دقت محسوس نہیں ہوتی کیونکہ ایک لمبے عرصہ کی مشق کی وجہ سے وہ اس کام میں تیراکوں کی طرح ہو جاتے ہیں یہی خوبی اللہ تعالیٰ نے صحابہؓ کی اس آیت میں بیان فرمائی ہے کہ اب توانہیں نیکیوں کے حصول میں بڑی محنت اور مشقت سے کام لینا پڑتا ہے لیکن ایک زمانہ آئے گا جب یہ ان کاموں میں تیراکوں کی طرح ہو جائیں گے اور ایک طبعی رغبت اور نشاط ان میں پیدا ہو جائے گا اور ایک دن یہ روحانی سمندر کے تیراک ہو جائیں گے جس طرح ایک ماہر تیراک دُور دُور تک تیرتا چلا جاتا ہے اور اُسے کوئی مشکل محسوس نہیں ہوتی اسی طرح وہ نیکیوں پر ایسا غلبہ حاصل کر لیں گے کہ ایک طبعی رغبت اور نشاط ان میں پیدا ہو جائے گا اور نیکیوں کے بجا لانے میں انہیں سرور محسوس ہو گا.لوگوں کو جھوٹ سے بچنے کیلئے بڑی بڑی کوششیں کرنی پڑتی ہیں مگر اُن کے لئے جھوٹ چھوڑ دینا کوئی بڑی بات نہیں.لوگوں کو صداقت پر قائم رہنا بڑا مشکل ہوتا ہے مگر اُن کے لئے صداقت سے کام لینا ایسا ہی ہے جیسے صداقت کی طرف ایک طبعی میلان اُن کے اندر پایا جاتا ہے.یہی حال دوسری نیکیوں کا ہے کہ اُن کے کرتے وقت انہیں یوں معلوم ہوتا ہے جیسے نیکیوں سے ان کی فطرت کو طبعی مناسبت پیدا ہو چکی ہے اور اب وہ کسی اور طرف جا ہی نہیں سکتے.گویا ہر نیکی انہیں یوں معلوم ہوتی ہے جیسے ماں کا دودھ ہے جس طرح بچہ اُس دودھ کو آسانی سے پی لیتا ہے اور اُسے کوئی بوجھ محسوس نہیں ہوتا اسی طرح کسی نیک بات پر بھی عمل کرنا اُن کے لئے بوجھ نہیں رہے گا.بلکہ وہ دلی شوق اور نشاطِ خاطر سے اس میں حصہ لیں گے.فَالسّٰبِقٰتِ سَبْقًا جب اُن میں نشاط پیدا ہو جائے گاتو اس کے بعد نیکی کی طرف ان کا ایک اور قدم اٹھے گا اور
Page 162
اُن میں یہ شوق پیدا ہو جائے گا کہ ہم اس میدان میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں.گویا وہ صر ف یہ نہیں دیکھیں گے کہ وہ اچھی طرح اور نشاطِ خاطر سے کام کر رہے ہیں بلکہ وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی بھی کوشش کریں گے اور قوتِ مسابقت کو حرکت میں لائیں گے.سخاوت ہر ایک کو آسان معلوم ہو گی مگر اس کے بعد وہ یہ کوشش کریں گے کہ ہم دوسروں سے زیادہ سخاوت کریں.عفّت ہر ایک کو آسان معلوم ہو گی مگر اس کے بعد ہر شخص کے اندر یہ جو ش پیدا ہو گا کہ میں دوسروں سے زیادہ عفیف بنوں.خوش خلقی ہر ایک کو آسان معلوم ہو گی مگر اس کے بعد ہر شخص کے اندر یہ جذبہ موجزن ہو گا کہ میںدوسروں سے زیادہ خوش خلق بنوں.رحم کرنا ہر ایک کو آسان معلوم ہو گا مگر اس کے بعد ہر شخص کے دل میں یہ جوش پیدا ہو گا کہ میں دوسروں سے زیادہ رحم کا نمونہ دکھائوں.گویا نیکیوں کے میدان میں اُن کا مقابلہ شروع ہو جائے گا اور ہر شخص کوشش کرے گا کہ میں دوسروں سے بڑھ جائوں.جب وہ اس مقام پر پہنچیں گے تو فَالْمُدَبِّرٰتِ۠ اَمْرًا یہ زائد بات بھی اُن میں پیدا ہو جائے گی کہ اُن میں سے ہر شخص اپنے آپ کو قوم کا ذمہ وار سمجھے گا.یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ کام فلاں کا ہے اور یہ کام فلاں کا.بلکہ ہر شخص سمجھے گا کہ میں ہی ساری جماعت کا ذمہ وار ہوں.ہندوستان میں بئے کی مثال مشہور ہے جو ایک چھوٹا سا جانور ہوتا ہے بعض یہی بات پِدّے کے متعلق کہتے ہیں کہ رات کو وہ اُلٹا سوتا ہے ایک دفعہ اس سے کسی نے پوچھا کہ تُو الٹا کیوں سوتا ہے تواُس نے جواب دیا کہ رات کو ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے اگر آسمان گر پڑے تو اُسے کون سنبھالے گا میں اس لئے اُلٹا سوتا ہوں کہ اگر آسمان گرا تو دنیا کو بچا لوں گا.یہ بظاہر ایک مضحکہ خیز مثال ہے لیکن انسانوں کے متعلق واقعہ یہی ہے کہ جو شخص کمال نیکی کو پہنچ جاتا ہے وہ ساری دنیا کی ذمہ واری اپنے اوپر لے لیتا ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ اس کی ذمہ واری فلاں پر ہے اور اس کی ذمہ واری فلاں پر.بلکہ وہ اپنے آپ کو ہی واحد ذمہ وار سمجھتا ہے جب یہ خوبی کسی قوم کے افراد میں پیدا ہو جائے تو وہ قوم کبھی تبا ہ نہیں ہو سکتی.ایک سو جائے گا تو دوسرا اُس کو جگانے کے لئے موجود رہے گا.آخر تمام لوگ ایک وقت میں توسو نہیں سکتے لازمًا کچھ حصہ سوئے گا اور کچھ حصہ بیدار رہے گا اور جب کچھ حصہ بیدار رہے گا تو اس کے یہ معنے ہیں کہ قوم کو بچانے والے افراد موجود رہیں گے اور وہ تباہی سے اُسے محفوظ رکھیں گے.غرض جس قوم میں بھی یہ نیکیاں پیدا ہو جائیں اس قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا وہ بڑھتی چلی جاتی ہے اور ساری دنیا پر غالب آجاتی ہے.سورۃ نازعات کی پہلی آیات کے چوتھے معنی ان آیات کے ایک چوتھے معنے بھی ہو سکتے ہیں اور وہ یہ کہ نَزَعَ کے معنے مشابہ ہو جانے کے بھی ہوتے ہیں چنانچہ نَزَعَ الْوَلَدُ اَبَاہُ اَوْ اِلٰی اُمِّہٖ کے معنے ہوتے ہیں اَشْبَہَ وہ اپنی ماں یا اپنے باپ کے مشابہ ہو گیا.اس لحاظ سے وَ النّٰزِعٰتِ غَرْقًا کے یہ معنے ہوں گے کہ مسلمان محمدرسول اللہ
Page 163
صلے اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کے نقشِ قدم پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں.حقیقت یہ ہے کہ جہاں تک رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا سوال ہے مکّہ والے اُن کو ذلیل سمجھا کرتے تھے مگر رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم کے متعلق وہ یہ کبھی نہیں کہتے تھے کہ آپ نعوذ باللہ ذلیل ہیں.بے شک ایک منافق نے ایک دفعہ آپ کو ذلیل کہہ دیا تھا مگر مکّہ والے تسلیم کرتے تھے کہ آپ کے اندر وہ تمام اوصاف پائے جاتے ہیں جو ایک کامیاب لیڈر کے اندر پائے جانے چاہئیں.اور وہ آپ کی قابلیت کے منکر نہیں تھے.بے شک وہ سمجھتے تھے کہ آپ غریب ہیں.آپ کے پاس مال و دولت نہیں ہے مگر جہاں تک ذاتی قابلیت کا سوال ہے وہ رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم کے قائل تھے آپ کو امین اور صدوق سمجھتے تھے اور اپنی قوم کے جھگڑوں میں آپ سے فیصلہ کرانے پر تیار ہو جایا کرتے تھے.پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم آج مسلمانوں کوذلیل سمجھتے ہو اور خیال کرتے ہو کہ اُن میں کوئی قابلیت نہیں مگر تمہیں کچھ پتہ بھی ہے کہ قابلیتیں کس طرح پیدا ہوا کرتی ہیں.قابلیت حاصل ہونے کا صرف ایک ہی طریق ہے کہ اچھا اُستاد مل جائے اور شاگرد اس کا کامل طور پر تتبع کرے.یہ واحد ذریعہ ہے اعلیٰ درجہ کی قابلیتیں اپنے اندر پیدا کرنے کا کہ کسی کو اچھا استاد مل جائے اور وہ اس استاد کی پوری پوری نقل کرے.مسلمانوں کا آنحضرت صلعم کے مشابہ ہو جانا پس فرماتا ہے وَ النّٰزِعٰتِ غَرْقًا یہ مسلمان تو وہ ہیں جو اپنے باپ کے مشابہ ہیں کیا تم نہیں دیکھتے کہ وہ محمد صلے اللہ علیہ وسلم کے نقشِ قدم پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں اور محمد صلے اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جن کی قابلیت کا تم میں سے کسی کو بھی انکار نہیں.تم اُسے دعویٰ سے پہلے ہی صدوق اور امین تسلیم کرتے تھے جیسا کہ نبیوں کے متعلق یہ ایک عام قاعدہ ہے کہ انہیں بعثت سے قبل قوم میں انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا اور ان کی قابلیتوں کا اعتراف کیا جاتا ہے چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام کے متعلق بھی قرآن کریم میں آتا ہے کہ لوگوں نے اُن سے کہا یَا صَالِحُ قَدْ کُنْتَ فِیْنَا مَرْجُوًّا قَبْلَ ھٰذَآ (ھود:۶۳)کہ اے صالح! ہم توتجھ پر امید لگائے بیٹھے تھے کہ تو ایک دن ہماری قوم کا لیڈر بنے گا مگر تُو نے ہماری امیدوں کو خاک میں ملا دیا.تو جہاں تک انبیاء کا تعلق ہے بعثت سے قبل ہی لوگ ان کی قابلیتوں کو تسلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں مگر یہ کہیں قانون نظر نہیں آتا کہ انبیاء پر ایمان لانے والوں کو دشمن ذلیل قرار نہ دیتے ہوں.ابتداء میں انبیاء پر ایمان لانے والے چونکہ زیادہ تر غرباء اور ادنیٰ طبقہ سے تعلق رکھتے ہیں اس لئے لوگ انہیں حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں.رسول کریم صلے اللہ علیہ وآلہٖ وسلم پر بھی ایمان لانے والے چونکہ زیادہ تر غرباء تھے(بخاری کتاب بدء الوحی باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ ) اس لئے مکّہ والے انہیں سخت حقارت سے دیکھتے تھے.اسی طرح ظاہری علوم کے لحاظ سے مسلمان بہت پیچھے تھے چنانچہ
Page 164
رسول کریم صلے اللہ علیہ وآلہٖ وسلم پر ایمان لانے والےنوجوانوں میں سے صرف حضرت زبیرؓ ہی لکھ سکتے تھے باقی صحابہؓ لکھنا بھی نہ جانتے تھے.لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ مسلمان اپنے باپ کی مشابہت اختیار کرر ہے ہیں.اور جب یہ اپنے باپ کے مشابہ ہو جائیں گے تو جو قابلیتیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جاتی ہیں وہی ان میں پیدا ہو جائیں گی.تم تسلیم کرتے ہو کہ محمد صلے اللہ علیہ وسلم امین ہیں.جب تم اس خوبی کو تسلیم کرتے ہواور دوسری طرف مسلمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ لازمی بات ہے کہ وہ بھی امین بن جائیں گے تم تسلیم کرتے ہو کہ محمد رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم صدوق ہیں اور تم یہ بھی دیکھ رہے ہو کہ مسلمان آپ کی اقتداء کی کامل کوشش کر رہے ہیں تو اس کا یہ ایک لازمی نتیجہ نکلنے والا ہے کہ جس طرح آپ صدوق ہیں اسی طرح مسلمان بھی راستبازی اور صداقت شعاری کا ایک نمونہ بن جائیں گے پس گو تمہیں آج مسلمانوں میں کوئی قابلیت نظر نہیں آرہی لیکن حصول علم کی خواہش اور اچھے نمونہ کی موجودگی کی وجہ سے ایک دن خود بخود ان میںبھی قابلیت پیدا ہو جائے گی.غَرْقًا کے معنے یہ ہیں کہ انہوں نے اتباع رسول کو حد تک پہنچا دیا ہے چنانچہ دیکھ لو مشابہتِ رسول کو مسلمانوں نے کس حد تک پہنچا دیا کہ سوائے اسلام کے اور کوئی مذہب ایسانہیں جس میں سُنت کا لفظ پایا جاتا ہو باقی مذاہب میں یا حدیث کا ذکر آتا ہے یا الہام کا.یا تو وہ کہیں گے قَالَ مُوْسٰی یعنی موسیٰ نے یوں کہا.قَالَ عِیْسٰی یعنی عیسیٰ نے یوں کہا.اور یا کہیں گے اُوْحِیَ اِلٰی مُوْسٰی موسیٰ کی طرف یہ وحی کی گئی یا اُوْحِیَ اِلٰی عِیْسٰی عیسیٰ کی طرف یہ وحی کی گئی.یہ کبھی نہیں کہیں گے کہ یہ موسیٰ ؑکی سنت ہے یا عیسیٰ ؑ کی سنّت ہے یا کرشن ؑ کی سنّت ہے یا رامچندر ؑ کی سنّت ہے.سنّت کی اصطلاح سوائے اسلام کے اور کسی مذہب میں نہیں پائی جاتی.یہ اصطلاح اسلام سے مخصوص ہے اور ہر مسلمان یہ معلوم کرنے کی کوشش کیا کرتا تھا کہ رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم اعمال کو کس طرح بجا لاتے تھے.پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہےوَ النّٰزِعٰتِ غَرْقًا یہ مسلمان محمد صلے اللہ علیہ وسلم کی نقل کو انتہا ءتک پہنچا دیں گے.اور جب آپ کی کامل طور پر نقل کر لیں گے تو محمد صلے اللہ علیہ وسلم کی قابلیتوں کے بھی وہ حامل ہو جائیں گے.پھر ان کی خوبیوں اور کمالات میں کیا شبہ ہو سکے گا جب کہ ہر شخص ان میں سےاپنے اپنے دائرہ میں ایک چھوٹا محمد بن جائے گا.چنانچہ رسول کریم صلے اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کی متابعت صحابہؓ جس طرح کیا کرتے تھے اس کا ثبوت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ایک واقعہ سے مل سکتا ہے.رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب بعض قبائلِ عرب نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کے خلاف جنگ کرنے کے لئے تیار ہو گئے.اُس وقت حالت ایسی
Page 165
نازک تھی کہ حضرت عمرؓ جیسے انسان نے مشورہ دیا کہ ان لوگوں سے نرمی کرنی چاہیے مگر حضرت ابو بکرؓ نے جواب دیا ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا طاقت ہے کہ وہ اس حکم کو منسوخ کر دے جو رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے خدا کی قسم اگر یہ لوگ رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اُونٹ کا گھٹنا باندھنے کی ایک رسّی بھی زکوٰۃ میں دیا کرتے تھے تو میں وہ رسّی بھی اُن سے لے کر رہوں گا اور اس وقت تک دم نہیں لوں گا جب تک وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے (بخاری کتاب الزکوٰۃ باب وجوب الزکاۃ )اگر تم اس معاملہ میں میرا ساتھ نہیں دے سکتے تو بے شک نہ دو میں اکیلا ہی اُن سے مقابلہ کروں گا.کس قدر اتباعِ رسول ہے کہ نہایت خطرناک حالات میں باوجود اس کے کہ اکابر صحابہ لڑائی کے خلاف مشورہ دیتے ہیں پھر بھی رسول کریم صلے اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کے حکم کوپورا کرنے کے لئے وہ ہر قسم کا خطرہ برداشت کرنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں.صحابہ کے آنحضرت صلعم کی کامل اقتداء کرنے کے بعض واقعات اسی طرح لشکرِ اسامہ کو روک لینے کے متعلق صحابہؓ نے بہت زور لگایا مگر حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر دشمن اتنا طاقتور ہو جائے کہ وہ مدینہ پر فتح پائے اور مسلمان عورتوں کی لاشیں کُتّے گھسیٹتے پھریں تب بھی میں اس لشکر کوجسے رسول کریم صلے اللہ علیہ وآلہٖ وسلم نے بھجوانے کے لئے تیار کیا تھا روک نہیں سکتا (تاریخ الخلفاء للسیوطی فصل فی ما وقع فی خلافۃ ابی بکر،البدایۃ والنھایۃ فصل فی تنقید جیش اسامۃ بن زید) اسی طرح کی ایک نقل کا واقعہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کا بھی ہے اُن کے متعلق لکھا ہے کہ وہ جب حج کے لئے جاتے تو ایک جگہ پیشاب کرنےکی طرز پر بیٹھ جاتے چونکہ ہر بار حج کو جاتے ہوئےاس طرح کیا کرتے تھے اس لئے ایک دفعہ اُن کے کسی دوست نے اُن سے کہا کہ آپ یہ کیا کرتے ہیں کہ ہر دفعہ اس مقام پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ آپ بعض دفعہ پیشاب نہیں کرتے یونہی بیٹھ کر آجاتے ہیں.آخر اس کی وجہ کیا ہے اور آپ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے جواب دیا کہ میں نے رسول کریم صلے اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کو ایک دفعہ یہاں پیشاب کرتے دیکھا تھا اس لئے میں جب بھی یہاں سے گزرتا ہوں میرا جی چاہتا ہے کہ میں بھی آپ کے فعل کی نقل کروں چنانچہ میں اس جگہ پیشاب کرنے کی طرز پر بیٹھ جایا کرتا ہوں.جس قوم نے اس حد تک نقل کو پہنچا دیا ہو اس کے متعلق ہر شخص فیصلہ کر سکتا ہے کہ وہ اخلاقی اور روحانی امور میں رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم کی نقل کرنے کی کس حد تک کوشش کرتی ہو گی.پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَ النّٰزِعٰتِ غَرْقًا بے شک مسلمان تمہاری نگاہ میں ذلیل ہیں لیکن ایک شخص جس کی قابلیت کے تم بھی معترف ہو محمد رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم ہیں اور تم دیکھ رہے ہو کہ مسلمان اُن کی کامل اقتداء کر رہے ہیں پس بے شک آج اُن میں قابلیت نہ ہو لیکن
Page 166
اس نقل کے نتیجہ میں ایک دن آئے گا جب یہ سارے اپنے اپنے درجہ کے مطابق محمدصلے اللہ علیہ وسلم بنے ہوئے ہوں گے اور وہی کمالات جو محمدصلے اللہ علیہ وسلم میں پائے جاتے ہیں ان میں بھی پیدا ہو جائیں گے اور محمد رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کے متعلق تم بھی مانتے ہو کہ اُن جیسا سردار اور لیڈر سارے عرب میں اور کوئی نہیں.جب یہ لوگ ایسے شخص کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں تو یہ ایک لازمی امر ہے کہ اس کے نتیجہ میں وہ خود بھی تمام خوبیوں کے حامل ہو جائیں گے.النّٰشِطٰتِ نَشْطًا میں مسلمانوں کے دور دور پھیل جانے کی پیشگوئی وَ النّٰشِطٰتِ نَشْطًا پھر دوسری خوبی ان میں یہ ہے کہ یہ دنیا میں پھیل جاتے ہیں.نَشَطَ کے ایک معنے پھیل جانے کے بھی ہوتے ہیں چنانچہ کہتے ہیں نَشَطَ مِنَ الْمَکَانِ: خَرَجَ.وَمِنْ بَلَدٍ اِلَی بَلَدٍ : قَطَعَ یعنی نَشْطٌ کے معنے سفر کرنا اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا بھی ہوتا ہے پس وَ النّٰشِطٰتِ نَشْطًا کے یہ معنے ہوئے کہ یہ لوگ دنیا میں پھیل جانے والے ہیں.ان کے دلوں میں اپنے وطن کی جھوٹی محبت نہیں بلکہ تم دیکھو گے کہ یہ اپنے وطن چھوڑنے کے لئے بھی تیار ہو جائیں گے مگر تمہارے ظلموں کو برداشت نہیں کریں گے.درحقیقت اسلام نے ہی سب سے پہلے اس مسئلہ کو پیش کیا ہے کہ وطن بے شک اچھی چیز ہے لیکن وطن سے زیادہ قیمتی چیز صداقت ہے.اگر وطن میںرہنے سے صداقت کو چھوڑنا پڑتا ہے تو تمہارا فرض ہے کہ وطن کو چھوڑ دو اور صداقت کو قائم رکھو.اسی کی طر ف اللہ ایک دوسری جگہ اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے وَ مَنْ يُّهَاجِرْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يَجِدْ فِي الْاَرْضِ مُرٰغَمًا كَثِيْرًا وَّسَعَةً١ؕ وَ مَنْ يَّخْرُجْ مِنْۢ بَيْتِهٖ مُهَاجِرًا اِلَى اللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَ قَعَ اَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ١ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ( النساء:۱۰۱)گویا بتایا کہ وطن بے شک اچھی چیز ہے جیسا کہ رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہےکہ حُبُّ الْوَطْنِ مِنَ الْاِیْمَانِ (تشیید المبانی فی تخریج احادیث مکتوبات الامام ربانی صفحہ۲۵) مگر جب اس محبت کے مقابلہ میں صداقت اور ایمان کی محبت آجائے اور تمہیں مظالم کا تختۂ مشق بنایا جائے تو وطن بے شک چھوڑ دو اور صداقت کی حفاظت کو مقدم رکھو.بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے دلوں پر وطن کی محبت اس قدر غالب ہوتی ہے کہ خواہ انہیں کس قدر دکھ دئے جائیں وہ وطن کو چھوڑنے کی طاقت اپنے اندر نہیں پاتے.مگر فرمایا یہ مسلمان وہ ہیں جنہیں ہم نے نَاشِطَاتِ بنایا ہے جو خدا تعالیٰ کے مقابلہ میں اپنے وطن کی کوئی حقیقت نہیں سمجھتے اور وقت آنے پر اس کو قربان کر دیں گے چنانچہ اس پیشگوئی کے بعد مسلمانوں نے دو دفعہ ہجرت کی.ایک دفعہ حبشہ کی طرف اور دوسری دفعہ مدینہ کی طرف پس مسلمانوں کو نَاشِطَاتِ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وطن کی جھوٹی محبت جوایک جگہ سے باندھ دیتی ہے اُن کے دلوں میں نہیں ہے
Page 167
اگر انہیں اپنا وطن قربان کرنا پڑا تو یہ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اس کو قربان کر دیں گے.نَازِعَاتِ غَرْقًا میں مسلمانوں کی جسمانی قربانی کی طرف اشارہ نَازِعَات میں مسلمانوں کی جسمانی قربانی کی طرف بھی اشارہ کیا گیا تھا کیونکہ جسمانی قربانی اُس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک محنت و مشقت برداشت کرنے کی عادت انسان میں پیدا نہ ہو.اور بتایا گیا تھا کہ مسلمان اس بارہ میں اعلیٰ درجہ کی صفات اپنے اندر رکھتے ہیں وہ بدیوں سے رُک بھی سکتے ہیں اور نیکیوں کے حصول کی تڑپ بھی رکھتے ہیں.بے شک قومی عادات کی وجہ سے بدیوں کے ترک کرنے میں انہیں محنت کرنی پڑتی ہے مگر وہ اس محنت کو برداشت کرتے چلے جاتے ہیں اور پھر صرف اسی حد تک نہیں بلکہ نیکیوں کے میدان میں بھی ترقی کرنے کی قابلیت رکھتے ہیں.اب نَاشِطَاتِ میں یہ بتایا کہ وہ نہ صرف جسمانی قربانی کرنے کا مادہ اپنے اندر رکھتے ہیں بلکہ وطن کو قربان کرنے کا مادہ بھی اُن کے اندر پایا جاتا ہے تم یہ نہ سمجھو کہ خواہ تمہاری طرف سے کس قدر مظالم ہوتے گئے وہ اُن کو برداشت کرتے چلے جائیں گے ہم تمہاری توجہ مسلمانوں کے اُن گروہوں کی طرف مبذول کراتے ہیں جو اپنے وطنوں کو چھوڑ کر باہر نکل جائیں گے.درحقیقت وطن کو چھوڑنا بھی قومی ترقی کا ایک ذریعہ ہوتا ہے.السّٰبِحٰتِ سَبْحًامیں مسلمانوں کے مفت طور پر قومی کام کرنے کی طرف اشارہ.پھر فرماتا ہے وَ السّٰبِحٰتِ سَبْحًا.سَبَحَ الرُّجُلُ کے معنے ہوتے ہیں تَصَرَّفَ فِیْ مَعَاشِہٖ یعنی آدمی اپنی روزی کمانے میں لگا ہوا ہے.پس اس آیت کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی تنخواہ کا قوم پر کوئی بار نہیں.اپنے دنیوی کام کر کے اپنا گزارہ کرتے ہیں اوراس وجہ سے قوم کو اَنْ گنْت کارکن مل رہے ہیں.درحقیقت قومی ترقی کے راستہ میں ایک بڑی روک یہ ہوتی ہے کہ مفت کام کرنے والے نہیں ملتے.اسی وجہ سےحکومتیں تنخواہ دار فوجیں رکھتی ہیں.تنخواہ دار مدرس رکھتی ہیں.تنخواہ دار کام کرنے والے رکھتی ہیں.اگر اسلام کی بھی یہی حالت ہوتی تو مسلمان کس طرح ترقی کر سکتے.مسلمانوں کے پاس نہ مال تھا کہ وہ تنخواہیں دے سکتے.نہ اتنی وسعت تھی کہ اس بار کو برداشت کر سکتے.اس لئے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں میں یہ جزبہ ودیعت کر دیا کہ وہ قومی کاموں کے لئے مفت خدمات پیش کرتے تھے.وہ گھر سے کھانا کھاتے اور ملک اورقوم کے لئے اپنے اوقات کو صرف کرتے گویا وہ ایسے وجود تھے جن کا جماعت پر کوئی بار نہیں تھا.بلکہ وہ مفت کے کارکن تھے.پس اللہ تعالیٰ ان آیات میں صحابہؓ کا نقشہ کھینچتاہے کہ ایک طرف وہ تمام بدیوں سے بچتے ہیں.دوسری طرف تمام نیکیوں کے میدان میں بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں.تیسری طرف وطن کی قربانی اُن کی نگاہوں میں بالکل ہیچ ہے اور چوتھی طرف ان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ کوئی پیسہ نہیں
Page 168
مانگتے.وہ یہ نہیں کہتے کہ جب ہم اس قدر کام کرتے ہیں تو ہمیں کچھ معاوضہ بھی ملنا چاہیے بلکہ وہ جس طرح ہو سکے اپنے گھر سے گزارہ کرتے اور قوم کا کام کرتے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہے کہ قوم کو اَنْ گنت کام کرنے والے مل رہے ہیں اور پھر یہ محمدصلے اللہ علیہ وسلم کے نقشِ قدم پر کامل طور پر چلنے والے ہیں.رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم انہیں لڑنے کے لئے کہتے ہیں تو یہ لڑنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں صلح کے لئے کہتے ہیں تو ـصلح کے لئے تیار ہو جاتے ہیں.صدقہ و خیرات کا حکم دیتے ہیں تو وہ اپنا سارا مال صدقہ وخیرات میں لٹانے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے وہی کچھ کرنا ہے جس کا محمدصلے اللہ علیہ وسلم انہیں حکم دیں اور پھر انہوں نے معاوضہ کے طور پر کوئی پیسہ نہیں مانگنا اس کا ذکر کے اللہ تعالیٰ کفار مکّہ کو بتاتا ہے تم غور کرو اور سوچو کہ تم ان مسلمانوں کا کہاں مقابلہ کر سکتے ہو.ہر مسلمان قومی خادم ہے.ہر مسلمان قومی سپاہی ہے.ہر مسلمان اپنا مال ٹیکس میں دینے کے لئے تیا ر ہے اور جب حالت یہ ہے تو تم ان کا مقابلہ کہاں کر سکتے ہو.فرض کرو مکّہ والوں میں سے پچاس فیصدی لوگ کام کرنے کے لئے تیار ہو جاتے تب بھی وہ مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ مسلمان سو فیصدی کام کرنے والے تھے اور سَو کا پچاس مقابلہ نہیں کر سکتے.پھر صحابہؓ کی یہ حالت تھی کہ وہ مفت کام کرتے تھے مگر مکّہ والوں میں یہ روح نہیں تھی.اسی طرح صحابہؓ جس شوق سے رسول کریم صلے اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کے احکام کی تعمیل کرتے تھے اس شوق سے مکہ والے اپنے سرداروں کے احکام کی کہاں اطاعت کر سکتے تھے.پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بیشک مسلمانوں کی تعداد تمہارے مقابلہ میں تھوڑی ہے مگر دُنیا میں تعداد سے فتح نہیں ہوتی بلکہ کام کرنے والوں سے فتح حاصل ہوتی ہے اور کام کرنے والے مسلمانوں میں زیادہ پائے جاتے ہیں.تم میں نہیں پائے جاتے.السّٰبِقٰتِ سَبْقًامیں مسلمانوں کے سب قوموں سے بڑھ جانے کی وجہ کا ذکر اس کے بعد فرماتا ہے فَالسّٰبِقٰتِ سَبْقًایہاں فاء کا استعمال لازمی نتیجہ کے معنوں میں ہوا ہے یعنی جب مسلمانوں کی حالت یہ ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہو گا کہ اس مفت خدمت کی وجہ سے اسلام کو اَنْ گنت کام کرنے والے مل جائیں گے اور لازمًا یہ ان لوگوں اور قوموں پر فتح پا جائیں گے جن میں مفت خدمت نہیں ہے.فرماتا ہے جب یہ سارے کے سارے اپنے گھر سے روٹی کھا کر خدمت کریں گے تو تم ان کا کس طرح مقابلہ کر سکو گے بے شک تعداد سے لحاظ سے تم زیادہ ہو مگر کام کرنے والوں کے لحاظ سے وہ زیادہ ہیں.اگر ایک قوم کی دس لاکھ تعدادہو اور اس میںسے سپاہی صرف چند سَو ہوں اور دوسری قوم کی تعداد اگرچہ چند سَو ہو مگر وہ ساری کی ساری سپاہی ہو تو یہ لازمی بات ہے کہ جب مقابلہ ہو گا زیادہ تعداد رکھنے والی قوم ہار جائے گی اور دوسری قوم جیت جائے گی.تو فرماتا ہے تمہارا یہ خیال غلط ہے کہ تم جیت
Page 169
جائو گے کام کرنے والوں کے لحاظ سے قوم زیادہ ہوا کرتی ہے نہ کہ افراد کی تعداد کے لحاظ سے قوم بڑی ہوتی ہے.اور جب دوسری اقوام کے کارکنوں پر یہ شوق اور خدمت میںغالب آجائیں گے تو لازمًا حکومت بھی اُن کے قبضہ میں آجائے گی.چنانچہ فرماتا ہے فَالْمُدَبِّرٰتِ۠ اَمْرًا جب یہ کام کے لحاظ سے تم پر غالب آگئے ہیں تو لازمًا ایک دن حکومت اُن کے ہاتھ میںآجائے گی تمہارے ہاتھ میں نہیں رہ سکتی.یہ چار معنے ہیں جو میں نے اِن آیات کے بتائے ہیں اور ان چاروں معنوں کے لحاظ سے آیات میں ایک ترتیب نظر آتی ہے اور جو اضطراب گزشتہ مفسرین کے معنوں میں پایا جاتا ہے کہ کبھی نَازِعَات سے مراد ستارے مراد لے لئے اور کبھی فرشتے اور پھر اگلی آیات کے متعلق کہنا کہ اُن میں بھی یہی مضمون پایا جاتا ہے وہ اضطراب ان معنوں میں سے کسی میں بھی نہیں ہےاور یہ سب کے سب ایسے معنے ہیں جو ترتیب کے ساتھ سب آیات پر چسپاں ہو جاتے ہیں.يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُۙ۰۰۷ ( ان کا ظہور اس دن ہو گا) جس دن جنگ ( کی تیاری) کرنے والی (قوم) جنگ کی تیاری کرے گی.حَلِّ لُغَات.تَرْجُفُ تَرْجُفُ رَجَفَ سے مضارع مؤنث غائب کا صیغہ ہے اور رَجَفَ (یَرْجُفُ) رَجْفًا کے معنے ہیں حَرَّکَہٗ فَرَجَفَ ھُوَاَیْ تَحَرَّکَ وَاضْطَرَبَ شَدِیْدًا کسی چیز کو زور سے حرکت دی اور وہ حرکت میں آگئی اور زور سے ہلنے لگی.اور جب رَجَفَ الرَّجُلُ کہیں تو معنے ہوں گے اِضْطَرَبَ شَدِیْدًا کانپنے لگا.اور رَجَفَتِ اَلْاَرْضُ کے معنے ہیں زُلْزِلَتْ.زمین ہلا دی گئی یعنی بھونچال آگیا.اور رَجَفَ الْقَوْمُ کے معنے ہیں تَھَیَّاءُ وْلِلْحَرْبِ.قوم لڑائی کے لئے تیار ہو گئی (اقرب) تفسیر.سورۃ نازعات کی پہلی پانچ آیات میں کی ہوئی پیشگوئیوں کے ظہور کا وقت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ یعنی اوپر کی باتیں اُس دن سے کامل طور پرظاہر ہونی شروع ہوں گی جب کانپنے والی کانپے گی یا یہ کہ جب اوپر کی تمام باتیں ہو جائیں گی تو پھر وہ دن آئے گا جسے ہم خصوصیت کے ساتھ تمہارے سامنے پیش کرتے ہیں اور وہ دن ایسا ہوگا کہ کانپنے والی کانپے گی.گویا ایک صورت میں یَوْمَ جو ظرف واقعہ ہوا ہے ان باتوں کے شروع ہونے سے تعلق رکھتا ہے اور دُوسری صورت میں اُن کے ختم ہونے سے تعلق رکھتا ہے.یَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَۃُ سے مراد یہ ہے کہ ایک دن آئے گا جب مسلمان قوم جنگ کے لئے تیار ہو جائے گی.تم
Page 170
آج اِن مسلمانوں پر پے در پے ظلم کر رہے ہو اور وہ تمہارے مقابلہ میں بالکل خاموش ہیں.تم خیال کرتے ہو کہ اِن مسلمانوں میں شاید مظالم برداشت کرتے کرتے مقابلہ کی حس ہی باقی نہیں رہی اُن کے دل مردہ ہو چکے ہیں اور اُن کے احساسات مٹ چکے ہیں لیکن تمہارا یہ خیال بالکل غلط ہے مسلمانوں کے دل مردہ نہیں ہوئے بلکہ وہ زندہ ہیں.اُن کے دل ان تکالیف کو دیکھ دیکھ کر جو تم محمد رسول اللہ صلے اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کو پہنچا رہے ہو تڑپ رہے ہیں.صرف ہم نے روکا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ تمہیں ان مظالم کا مزہ نہیں چکھا سکتے اور پیچ وتاب کھا کر رہ جاتے ہیں.گویا رَاجِفَۃ کہہ کر بتا دیا کہ مسلمانوں کے دل زندہ ہیں یہ نہ سمجھو کہ مظالم نے اُن کے احساسات کو مٹا ڈالا ہے.وہ صرف ہماری اجازت کے منتظر بیٹھے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ وہ تمہارے مقابلہ میں ہاتھ نہیں اٹھاتے لیکن یاد رکھو یَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَۃُ جس دن یہ بڑے حسّاس دل اپنے جوش واضطراب کا اظہار کریں گے اُس دن یہ تمام باتیں جن کا ہم نے اُوپر ذکر کیا ہے ظاہر ہونی شروع ہو جائیں گی.ابھی ہم ان کے اخلاق کی تکمیل کر نا چاہتے ہیں اگر آج ہی اُن کو لڑائی کی اجازت دے دیں تو وہ اعلیٰ اخلاق جو ہم اُن میں پیدا کرنا چاہتے ہیں کس طرح پیدا ہو سکتے ہیں.ہم ابھی اُن پر ظلم کروائیں گے تاکہ اُن میں مادۂ صبر پیدا ہو جائے.اسی طرح وہ اخلاق پیدا ہو جائیں جو ظلم کے نتیجہ میں ظاہر ہوا کرتے ہیں.پس تم اُن کی موجودہ حالت پر قیاس مت کرو.تم اُس دن کو یاد کرو جب اُن کے حساس دل اپنے زندہ ہونے کا ثبوت پیش کر دیں گے.نَازِعَات کے معنے اگر تیر اندازی کرنے والوں کے کئے جائیں تو اس آیت کا مطلب یہ ہو گا کہ وہ تیر اندازی اُس دن شروع ہو گی جب اُن کے حساس دل اضطراب شدید کا اظہار کرنا شروع کر دیں گے.اور چونکہ رَجْفٌ کے ایک معنے قوم کے لڑائی کے لئے تیار ہونے کے بھی ہیں اس لئے یَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَۃُ کے یہ معنے بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ قوم جس کے دل لڑائی کے لئے مستعد ہیں مگر ہماری طرف سے اجازت نہ ہونے کی وجہ سے رُکے ہوئے ہیں ایک دن جنگ کیلئے تیّار ہو جائے گی یعنی امن اور صلح کے شیدائی آخر ظلموں کو دین کے لئے نقصان دہ دیکھ کر خدا تعالیٰ کے حکم سے جنگ پر آمادہ ہو جائیں گے یا جب اوپر کی باتیں ہو جائیں گی اُس کے بعد ہم اس دن کو لائیں گے.تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُؕ۰۰۸ اس (جنگ کی تیاری) کے بعد (اس قسم کی ) پیچھے آنیوالی (ایک اور)گھڑی آئے گی.حَلّ لُغَات.اَلرَّادِفَۃُ.الرَّادِفَۃُ رَدَفَ سے اسم فائل مؤنث کا صیغہ ہے اور رَدَفَ (یَرْدُفُ وَرَدِفَ
Page 171
یَرْدَفُ) رَدَفًا کے معنے ہیں تَبِعَہٗ اس کے پیچھے پیچھے آیا(اقرب) پس رَادِفَۃٌ کے معنے ہوئے پیچھے آنےوالی.تفسیر.بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص کے اندر بظاہرلڑائی کا بڑا جوش نظر آتا ہے اور وہ کہتا ہے میں یوں کردوں گا وُوں کردوں گا.مگر اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اگر اسے ایک تھپڑ بھی لگ جائے تو اس کا سارا جوش وخروش جاتا رہتا ہے اور وہ خاموش ہو کر بیٹھ جاتا ہے.اسی طرح بعض لوگ اپنے آپ کو بڑا بہادر سمجھتے ہیں مگر وقت آنے پر اُن کی حقیقت کُھل جاتی ہے اور معلوم ہو جاتا ہے کہ ان کی بہادری کے دعوے سب غلط تھے.میں نے کئی دفعہ اس شخص کی مثال سنائی ہے جو ایک گودنے والے کے پاس گیا اور اُسے کہنے لگا کہ میرے بازو پر شیر کی تصویر گود دو.اُسے بھی یہ وہم تھا کہ میں بہت بہادر ہوں.جب جراح نے سُوئی چبھوئی تو جھٹ چونک کر کہنے لگا کیا بنانے لگے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ شیر کا کان.کہنے لگا اگر شیر کا کان نہ ہوتو آیا شیر رہتا ہے یا نہیں رہتا؟ اس نے کہا کیوں نہیں رہتا.وہ کہنے لگا تو پھر کان چھوڑ دو اور کوئی اور حصہ بنائو.پھر اُس نے سوئی ماری تو اُس نے دوبارہ شور مچا دیا اور کہنے لگا اب کیا کرنے لگے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ شیر کا دوسرا کان بنانے لگا ہوں.اُس نے کہا اگر یہ کان نہ ہو تو پھر یہ شیر رہتا ہے یا نہیں رہتا؟ وہ کہنے لگا رہتا کیوں نہیں.کہنے لگا اچھا تو پھر اس کوبھی چھوڑو اور آگے چلو.اسی طرح وہ ہر دفعہ یہی کہتا چلا گیا.آخر گودنے والے نے سوئی رکھ دی اور کہنے لگا اب تو کچھ بھی نہیں بن سکتا.تو بعض فطرتیں ایسی ہوتی ہیں کہ بہادری کا دعویٰ تو بہت کرتی ہیں مگر وقت پر بزدل ثابت ہوتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تَتْبَعُھَا الرَّادِفَۃُ یہ نہیں ہو گا کہ مسلمان پھر اپنے ہاتھ سے تلوار چھوڑ دیں بلکہ ایک دفعہ تلوار اٹھے گی تو پھر پے در پے جنگیں ہوتی ہی چلی جائیں گی.یہ نہیں ہو گا کہ مسلمان ڈر جائیں یا ایک حملہ کے بعد دوسرا حملہ نہ کریں بلکہ متواتر اور مسلسل جنگیں ہوں گی اور وہ اُس وقت تک تلوار ہاتھ سے نہ رکھیں گے جب تک فتح نہ پائیں.قُلُوْبٌ يَّوْمَىِٕذٍ وَّاجِفَةٌۙ۰۰۹ اس دن کچھ ( لوگوں کے)دل دھڑک رہے ہوں.حَلّ لُغَات.وَاجِفَۃٌ وَجَفَ سے اسم فاعل مؤنث کا صیغہ ہے.وَجَفَ (یَجِفُ) وَجْفًا وَوَجِیْفًاوَ وَجُوْفًا کے معنے ہوتے ہیں اِضْطَرَبَ وہ کانپنے لگا اور جب قلب کے لئے یہ لفظ استعمال ہو تو اس کے معنے خفقان کے ہوتے ہیں چنانچہ کہتے ہیں وَجَفَ الْقَلْبُ وَجِیْفًا اَیْ خَفَقَ یعنی دل دھڑکنے لگا.اور جب گھوڑے یا
Page 172
اونٹ کے متعلق یہ لفظ استعما ل ہو تو اس کے معنے ہوتے ہیں عَدَاوَسَارَالْعَنَقَ.وہ تیز دوڑا ور عنق (تیز چال) چال چلا (اقرب)پس قُلُوْبٌ يَّوْمَىِٕذٍ وَّاجِفَةٌ کے معنے ہوں گے اس دن کچھ دل ایسے ہوں گے جو دھڑک رہے ہوں گے.تفسیر.غلبہ اسلام کے ظہور سے قیامت کےبرپا ہونے کے متعلق کفار کے دلوں میں خیالات جیسا کہ سورۂ نبأ کی تفسیر میں بیان کیا جاچکا ہے اللہ تعالیٰ ایک ہی وقت میں قرآن اور اسلام کے غلبہ اور قیامت کا ذکر کرتا ہے اور اسلام کے غلبہ کو قیامت کی دلیل کے طور پر پیش کرتا ہے کہ جو خدا اتنا عظیم الشان تغیّرپیدا کر سکتا ہے تمہیں یقین رکھنا چاہیے کہ وہ مرنے کے بعد بھی زندگی بخش سکتا ہے.اسی کی طرف اس آیت میں اشارہ کیا گیا ہے کہ جب یہ حالات رُونما ہوں گے بڑے بڑے صنادید مارے جائیں گے اور مسلمان کفار کو مغلوب کر لیں گے تو اُن کے دلوں میںیہ شبہ پیدا ہو نا شروع ہو جائے گاکہ کہیں سچ مچ قیامت بھی تو نہیں آنےوالی.جب ایک بات پوری ہونی شروع ہو گئی ہے تو دوسری بات جس کا اسی کےساتھ تعلق تھا وہ بھی پوری ہو سکتی ہے.پس اُس دن کفار گھبرا جائیں گے اور آثار شکست ظاہر ہو جائیں گے یہاں تک کے کفار کے دل میں اپنے عقیدۂ قیامت کے انکار کے متعلق بھی شبہات پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے اور وہ کہیں گے ارے کہیںقیامت بھی تو نہیں آنیوالی جس کا مسلمانوںکی طرف سے ذکر کیا جا رہا تھا.اَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌۘ۰۰۱۰ اور ان کی نظریں خوف سے جھکی ہوئی ہوں گی.حَلّ لُغَات.اَلْخَاشِعَۃُ الْخَاشِعَۃَ خَشَعَ سے اسم فاعل مؤنث کا صیغہ ہے اور خَشَعَ بِبَصَرِہِکے معنے ہوتے ہیں غَضَّہَ آنکھ کو نیچا کیا.وَغَضَّ بَصَرُہٗ: اِنْکَسَرَ اس کی آنکھ انکسار سے جھک گئی.وَفِیْ النَّھَایَۃِ اَلْخُشُوْعُ فِیْ الصَّوْتِ وَالْبَصَرِ کَالْخُضُوْعِ فِیْ الْبَدَنِ.نھایۃ کے مصنف لکھتے ہیں کہ جس طرح بدن کی عاجزی اور انکساری کے اظہار کے لئے خضوعؔکا لفظ استعمال کرتے ہیں اسی طرح آنکھ اور آواز سے عجز کے اظہار کو خشوع کہتے ہیں.(اقرب) تفسیر.اَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌمیں ھا کی ضمیر کا مرجع اَبْصَارُھَا کی ضمیر قلوب کی طرف جاتی ہے اور اَبْصَار کے معنے آنکھوں کے ہوتے ہیں.یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ دلوں کی تو آنکھیں نہیں ہوتیں پھر اَبْصَارُھَا کیوں کہا گیا ہے.اس کا جواب یہ ہے کہ اَبْصَارُھَا میں ھَاء سے مراد اہل قلوب ہیں جیسا کہ یَقُوْلُوْنَ
Page 173
سے ظاہر ہے فرماتا ہے یَقُوْلُوْنَ ئَ اِنَّا لَمَرْدُوْدُوْنَ فِیْ الْحَافِرَۃٍ اس پر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ اگر اہل قلوب مراد ہیں تو پھر ضمیر مؤنث کیوں ہے ؟اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ یہاں اہل قلوب مراد ہیں.اس لئے قلوب کی طرف اضافت کے باعث ضمیر مؤنث آسکتی ہے جیسے تَسُرُّالنّٰظِرِیْنَ (البقرۃ :۷۰)میں ہے یہ عربی کا قاعدہ ہے کہ اگر کوئی لفظ مؤنث یا مذکر کی طرف مضاف ہو تو مضاف الیہ کی مطابقت میں اسے بھی مؤنث یا مذکر قرار دے دیتے ہیں.دوسرا جواب یہ ہے کہ اَبْصَار.بَصَرٌ کی جمع ہے اور بَصَرٌ کا لفظ حَاسَّۃُ الرُّوْیَۃ کے معنوں میںبھی استعمال ہوتا ہے اور اَلْعَیْن کے معنوں میں بھی استعمال ہو تا ہےاور اَلْعِلْمُ کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے (اقرب) اور علم کی ضمیر قلوب کی طرف پھیری جا سکتی ہے یعنی ان کے قلوب میں عقل اور فہم کی جو حس ہے وہ منکسر ہو جائے گی اور انہیں معلوم ہو گا کہ ان کے دلوں جو علم کے دعوے تھے سب غلط تھے.اور اگر اَبْصَار سے ظاہر ی آنکھیں مراد لیں تو جیسا کہ اوپر بتا یا گیا ہے آیت کے معنے یہ ہوں گے کہ اس دن کچھ دل دھڑک رہے ہوں گے اور اُن اہل قلوب کی آنکھیں ذلّت اور ندامت سے جھکی ہوئی ہوں گی.وہ شرمندہ ہوں گے کہ محمدصلے اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا تھا وہ پورا ہوگیا.اس مشاہدہ اور معائنہ کے بعد اُن کی آنکھیں شرمندگی اور ذلّت اور انکسار سے جھک جائیں گی.یعنی یَالَیْتَنِیْ کُنْتُ تُرَابًا والا نظارہ دیکھ کر کسی کے سامنے آنکھ نہ اٹھا سکیں گے اور دل میں قیامت کے انکار کے متعلق بھی شبہ پیدا ہو جائے گا کہ جس طرح یہ بات پوری ہوئی کیا وہ بھی تو پوری نہ ہو جائے گی.دوسرے معنے اس کے یہ ہیں کہ اُس دن کچھ دل دھڑک رہے ہوں گے.اُن کی بصیرتیں اور علوم سب باطل ہو جائیں گے اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اُن کے علم وفہم کے دعوے سب غلط تھے.يَقُوْلُوْنَ ءَاِنَّا لَمَرْدُوْدُوْنَ۠ فِي الْحَافِرَةِؕ۰۰۱۱ (اور) وہ کہیں گے کیاہمیں اپنے رستے پر اُلٹے پائوں لوٹایا جائے گا.حَلّ لُغَات.اَلْحَافِرَۃُ الحَافِرَۃُ مؤنث ہے اَلْحَافِرُ کی اور اس کے معنے ہیں اَلْخَلْقَۃُ الْاُوْلٰی.پہلی پیدائش.کہتے ہیں رَجَعَ عَلٰی حَافِرَتِہٖ وَفِیْ حَافِرَتِہٖ اَیْ فِیْ طَرِیْقِہِ الَّتِیْ جَائَ فِیْھَا یعنی رَجَعَ عَلٰی حَافِرَتِہٖ کہیں تو اس کے معنے یہ ہوتے ہیں کہ وُہ اُسی طرف چلا گیا جس طرف سے آیا تھا.نیز کہتے ہیں فُلَانٌ رَجَعَ فِیْ حَافِرَتِہٖ: شَاخَ وَھَرِمَ یعنی وہ بڈھا ہوگیا.وَرَجَعَ عَلٰی حَافِرَتِہٖ یُقَالُ اَیْضًا لِمَنْ کَانَ فِیْ اَمْرٍ فَخَرَجَ مِنْہُ
Page 174
ثُمَّ عَادَ اِلَیْہِ (اقرب) جو شخص کوئی کام کرتا ہوا چھوڑ دے اور پھر اُسے کرنے لگ جائے اس کے متعلق کہتے ہیں کہ رَجَعَ عَلٰی حَافِرَتِہٖ.تفسیر.يَقُوْلُوْنَ ءَاِنَّا لَمَرْدُوْدُوْنَ۠ فِي الْحَافِرَةِسے مراد یہ ہے کہ جب کفار ایک پیشگوئی کو پورا ہوتے ہوئے دیکھیں گے تو اُن کے دل دھڑکیں گے اور وہ کہیں گے کیوں جی ایک بات تو پوری ہو گئی.کیا دوبارہ زندہ ہونے والی بات بھی پوری ہو جائے گی یعنی خُود بخو اُن کے دل میں سوال اُٹھنا شروع ہو جائے گا یا وہ آپس میں ایک دوسرے سے کہیں گے کہ ایک بات تو ہو گئی کیا اس سے ہم یہ نتیجہ نکال لیں کہ قیامت کا مسئلہ بھی سچ مچ صحیح ہے اور کیا اب اس طرح ہو کر رہے گا اگر ایسا ہوا تو ہمیں بڑا نقصان پہنچے گا.ءَاِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَةًؕ۰۰۱۲قَالُوْا تِلْكَ اِذًا کیا ( اس حالت میں بھی کہ) جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے (ایسا ہو گا).كَرَّةٌخَاسِرَةٌۘ۰۰۱۳ وہ کہتے ہیں (اگر ایسا ہوا) تب تو یہ بڑی گھاٹے والی واپسی ہو گی حل لغات.نَخِرَۃٌ نَخِرَالْعَظْمُ کے معنے ہوتے ہیں بَلِیَ وَتَفَتَّتَ ہڈیاں گل سڑ گئیں اور ٹکڑے ٹکڑے ہوگئیں (اقرب) اَلْعِظَامُ النَّخِرَۃُ: اَلْبَالِیَۃُالْمُتَفَتِّتَۃُ بوسیدہ اور گلی سڑی ہڈیاں (اقرب) اَلْکَرَّۃُ کے معنے ہیں لوٹنا اور اَلْکَرَّۃُ اَلْخَاسِرَۃُ کے معنے ہیں نقصان دِہ لوٹنا.تفسیر.ءَاِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَةً میں سوال انکاری نہیں بلکہ استعجاب کا سوال ہے یعنی کفّار تعجب سے کہتے ہیں کہ ایک بات تو مسلمانوں کی پوری ہو گئی.دوسری بات جو مسلمان کہا کرتے تھے کہ جب ہڈیاں گل سڑ جائیں گی.اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گی تو پھر دوبارہ اُن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے زندہ کر دیا جائے گا.پس جب ان کی ایک بات پوری ہوتی نظر آگئی ہے تو دوسری بات بھی پوری ہو سکتی ہے گویا وہ جو کہا کرتے تھے کہ مرنے کے بعد انسان دوبارہ زندہ کیا جائے گا یہ بات تو ٹھیک ہوتی نظر آتی ہے.قَالُوْا تِلْکَ اِذًا کَرَّۃٌ خَاسِرَۃٌ کفار کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہوگا تو یہ ہمارا لوٹنا بڑا نقصان دہ ہو گا اس لئے کہ محمد رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی تھی کہ دو قیامتیں آنے والی ہیں.ایک قیامت میرا غلبہ ہے اور ایک
Page 175
قیامت وہ ہے جب مرنے کے بعد ہر انسان کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا اور اُسے اپنے اعمال کا جواب دینا پڑے گا.ہم نے ان دونوں قیامتوں کا انکار کیا اور کہا کہ ہم کسی بات کو ماننے کیلئے تیار نہیں.چنانچہ ہم نے اس کا مقابلہ کیااور اس کو مٹانے کیلئے اپنی تمام کوششیں صرف کر دیں مگر جب بھی ہم نے اُس کے مقابلہ میں سر اٹھایا ہم کچلے گئے اور ہمیں ذلّت کے ساتھ ناکام ہونا پڑا.اس کے بعد ساری قوم نے مل کر محمدرسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کو گرانے اور آپ کو اپنے مقصد میں ناکام کرنے کی کو شش کی مگر پھر بھی ہم مارے گئے.پس جب ہم تیاری کر کے مارے گئے تو جہاں ہم بے تیاری کے جائیں گے وہاں ہمارا کیا حال ہو گا.اُس دن کے لئے توہم نے کوئی بھی تیاری نہیں کی.پس اگر وہ بات بھی پوری ہوئی تو پھر تو ہمارا بُرا حال ہو گا کیونکہ اس کے لئے ہم نے کوئی تیاری نہیں کی.اس دنیوی دن کے لئے تو تیاری کی تھی پھر بھی ذلیل ہو گئے وہ دن جس کے لئے تیاری نہیں کی اُس دن کیا حال ہو گا.وہ ہمارا لوٹنا توبڑا نقصان دِہ ہو گا.اس جگہ دوزخ کا ذکر یہ بتانے کے لئے کیا گیا ہے کہ یہاں قیامت اور غلبۂ رسول دونوں کا اکٹھا ذکر ہو رہا تھا.اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ جب اِن میں سے ایک بات پوری ہو جائے گی تو کفار خود بخود اس سے یہ استدلال کرنا شروع کر دیں گے کہ جو دوسری بات کہی گئی تھی معلوم ہوتا ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی اور اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں بڑا نقصان ہو گا کیونکہ ہم نے تو اُس دن کے لئے تو کوئی تیاری نہیں کی.اس کے بعد پھر اصل مضمون کی طرف رجوع کرتا ہے.فَاِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَّاحِدَةٌۙ۰۰۱۴ پس (حقیقت میں) یہ (جنگ کی تیاری) ایک (الٰہی) ڈانٹ (ڈپٹ کا نتیجہ) ہو گی.حَلِّ لُغَات.زَجْرَۃٌ زَجْرَۃٌ زَجَرَ سے ہے اور زَجَرَہٗ عَنْ کَذَا زَجْرًا کے معنے ہوتے ہیں مَنَعَہٗ وَنَھَاہٗ اس کو کسی چیز سے سختی سے روکا اور منع کیا وَیُقَالُ اَصْلُ الزَّجْرِ اَلطّرْدُ مَعَ الصَّوْتِ یعنی زجر کے اصل معنے آواز کے ساتھ دوڑانے کے ہیں چنانچہ کہتے ہیں زَجَرَالْبَعِیْرُ: صَاحَ بِہٖ لِیَسُوْقَہُ زور زور سے آوازیں دے کراونٹ کو ہانکا اور جب زَجَرَتِ النَّاقَۃُ بِمَا فِیْ بَطْنِھَا کہیں تو معنی ہوں گے رَمَتْ بِہٖ اونٹنی نے اپنا بچہ پھینک دیا اور زَجَرَ الطَّیْرَ کے معنے ہوتے ہیں تَفَائَ لَ بِہٖ فَتَطَیَّرَ فَنَھَرَہٗ یعنی طیر سے تفائول لیا اور پھر منحوس فال نکلنے پر پرندے کو اڑا دیا.اسی طرح کہتے ہیں فُلَانٌ یَزْجُرُ الطَّیْرَ یعنی اُس نے پرندہ اڑاد یا.دائیں طرف گیا تو نیک فال
Page 176
لی.بائیں طرف گیا تو بُری فال لی (اقرب) گویا زجر کے اور معنوں کے علاوہ ایک معنے روکنے اور منع کرنے کے بھی ہیں اور ایک معنے اونٹوں کو شور کے ساتھ ہنکا کر لے جانے کے ہیں.پس زَجْرَۃٌ وَاحِدَۃٌ کے معنے ہوئے ایک دفعہ دھکیل کر لے جانا یا ہنکا کر لے جانا.تفسیر.اِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَّاحِدَةٌ میں جنگ بدر کا نقشہ فرماتا ہے فَاِنَّمَا ھِیَ زَجْرَۃٌ وَّاحِدَۃٌ ارے میاں ابھی تمہارے دل دھڑکنے لگ گئے.یہ درحقیقت جنگ بدر کی طرف اشارہ ہے اور فرماتا ہے کہ یہ جو ہم نے کہا تھا کہ یَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَۃُ تَتْبَعُھَا الرَّادِفَۃُ اُس کا تو ابھی ہم نے صرف پہلا نمونہ دکھایا ہے اور ابھی سے تم حواس باختہ ہو گئے اور تمہارے دل دھڑکنے لگ گئے حالانکہ ابھی تَتْبَعُھَا الرَّادِفَۃُ والی پیشگوئی پوری ہونی باقی ہے اور تمہیں ہم نے کئی دفعہ ان میدانوں میں ہنکا کر لے جانا ہے.یہ ویسا ہی فقرہ ہے جیسے ایک شاعر نے کہا کہ ؎ ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا آگے آگے دیکھیو ہوتا ہے کیا فرماتا ہے فَاِنَّمَا ھِیَ زَجْرَۃٌ وَّاحِدَۃٌ یہ عذاب جس کا ہم نے ذکر کیا ہے عذابوں کے لمبے سلسلہ میں سے پہلا عذاب ہو گا اور اسی کے دیکھنے سے تمہارے حوصلے پست ہو جائیں گے حالانکہ ہم تمہیں اور تمہاری قوم کے سرداروں کو بار بار جمع کریں گے اور بار بار مسلمانوں کے مقابلہ میں تم شکست کھائو گے.ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے بدر کی جنگ کا نقشہ کھینچ دیا ہے.بدر کی جنگ میں نہ مسلمان لڑنے کی نیت سے نکلے تھے اور نہ کفار لڑنے کی نیت سے نکلے تھے.مسلمان مدینہ سے صرف اس لئے نکلے تھے کہ انہیں معلوم ہوا کہ شام سے کفار کا ایک قافلہ آرہا ہے اور چونکہ یہ ایک غیر معمولی قافلہ تھا جس میں قریش کے ہرمرد و عورت کا تجارتی حصہ تھا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے متعلق رئوساء قریش کی یہ نیت تھی کہ اس کا منافع مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے میں استعمال کیا جائے گا.چنانچہ تاریخ سے بھی ثابت ہے کہ یہی منافع جنگ اُحد کی تیاری میں صرف کیا گیا (الطبقات الکبریٰ لابن سعد غزوۃ رسول اللہ احدا) پس علاوہ اس کے کہ وہ قوم کی قوم مسلمانوں سے برسرِ پیکار رہتی تھی اپنے روپیہ اور مال کے ذریعہ سے بھی مسلمانوں کے خلاف مختلف قسم کے منصوبے سوچتی رہتی تھی اور یہ مال انہیں زیادہ تر تجارت سے حاصل ہوتا تھا.دوسرے مسلمانوں کو علم تھا کہ کفار مکہ بھی اسی قافلہ کی پیشوائی کو ایک لشکر لے کر نکلے ہیں پس مسلمان یہ بتانا چاہتے تھے کہ ہم تم سے ڈرتے نہیں لیکن اُن کو قطعی طور پر یہ علم نہ تھا کہ کفار سے جنگ ضرور ہو جائے گی.پس چونکہ اس روپیہ کا استعمال مسلمانوں کے خلاف ہونے والا تھا.اور دوسرے کفار مکہ ایک لشکر
Page 177
کے ذریعہ سے مسلمانوں کے رعب کو مٹانے کے لئے نکلے تھے اس لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہؓ کو لے کر نکلے کہ تا علاقہ پر کفار کا رعب نہ پڑے گو پہلے بھی رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے اشارات ہو رہے تھے جن سے ظاہر ہوتا تھا کہ کفار سے جنگ ہونے والی ہے مگر یہ امر واضح نہ تھا کہ ابھی ایسا ہونے والا ہے لیکن جب آپ لشکر لے کر نکلے تو آپ کو وحی سے بتایا گیا کہ دراصل کفار سے لڑائی ہونی ہے قافلہ سے مقابلہ نہیں ہو گا.مگر رسول کریم صلے اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ابھی یہ بات بتائیں نہیں جس وقت آپ بدر کے قریب پہنچے تو اُس وقت آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے کہ قافلہ سامنے آجائے یا دشمن کے لشکر سے ہی مقابلہ ہو جائے اُس وقت صحابہؓ نے کہا یا رسول اللہ! جو صورتِ حالات بھی پیدا ہو ہم اس کا مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہیں مگر اب بھی اُن کے ذہن میں یہی تھا کہ لشکر سے کہاں مقابلہ ہونا ہے قافلہ والوں سے ہی مقابلہ ہو گا.مگر جب آپ بدر کے مقام پر پہنچے تو وہاں کفار کا لشکر موجود تھا اُس وقت آپ نے صحابہؓ سے فرمایا کہ بولو اب کیا رائے ہے؟ صحابہؓ نے کہا یا رسول اللہ ہم لڑائی کے لئے تیار ہیں.یہی وجہ ہے کہ اس جنگ میں صرف تین سو تیرہ صحابہ شامل ہوئے ورنہ مسلمانوں کی تعداد اس سے زیادہ تھی.اس قدر تھوڑی تعداد میں مسلمان اسی لئے رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے تھے کہ ان کا خیال تھا کہ غالبًا مقابلہ کوئی نہ ہوگا اس لئے زیادہ آدمیوں کی ضرورت نہیں مگر جب قافلہ کی بجائے لشکر سے مقابلہ ہو گیا تو بعض صحابہؓ نے رسول کریم صلے اللہ علیہ وآلہٖ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! ہم آپ کے لئے مقامِ حفاظت بنا دیتے ہیں تا کہ آپ محفوظ رہیں.اور آپ کے پاس ایسی تیز رفتار اونٹنیاں باندھ دیتے ہیں جو نہایت مضبوط ہوں.یا رسول اللہ! اگر ہم سب کے سب اس جنگ میں مارے جائیں تو ہماری درخواست ہے کہ آپ ان تیز رفتار اونٹنیوں پر سوار ہو کر مدینہ تشریف لے جائیں وہاں ہمارے بھائی موجود ہیں جن کے دلوں میں ویسا ہی اخلاص موجود ہے جیسا ہمارے دلوں میں ہے اور جو دین کے لئے قربانی کی ویسی ہی روح رکھتے ہیں جیسے ہم رکھتے ہیں مگر انہیں معلوم نہ تھا کہ جنگ ہونے والی ہے ان کا یہی خیال تھا کہ شاید جنگ نہ ہواور اسی لئے وہ ساتھ نہیں آئے.آپ ہمارے اُن بھائیوں کو ساتھ لے کر پھر ان کفار کا مقابلہ کر سکتے ہیں (السیرۃالحلبیۃ باب غزوۃ بدر)دوسری طرف کفار کا یہ حال تھا کہ جب انہوں نے سنا کہ قافلہ بچ کر نکل آیا ہے تو ابو جہل اور دوسرے بڑے بڑے سرداروں نے کہا چلو ہم ذرا عیش کر آئیں اور خوشی منائیں کہ مسلمان ہمارے قافلہ کو روک نہیں سکے.پس وہ بھی لڑائی کے ارادہ سے نہیں نکلے تھے بلکہ اُن کا منشاء یہ تھا کہ ہم تین دن دعوتیں کریں گے شرابیں پئیں گے اور خوب عیش منائیں گے اور علاقہ پر رعب ڈالیں گے.پس اپنی طرف سے وہ عیش منانے کے لئے آئے تھے اور سمجھتے تھے
Page 178
کہ مسلمانوں میں یہ جرأت کہاں ہو سکتی ہے کہ وہ ہمارے مقابلہ میں آئیں.اِدھر مسلمان یہ سمجھتے تھے کہ ہم کسی یقینی لڑائی کے لئے نہیں جا رہے.مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص حکمت سےدونوں کو ایک مقام پر لڑائی کے لئے جمع کر دیا.دوسری جگہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ اِذْ اَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَ هُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوٰى وَ الرَّكْبُ اَسْفَلَ مِنْكُمْ١ؕ وَ لَوْ تَوَاعَدْتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيْعٰدِ١ۙ وَ لٰكِنْ لِّيَقْضِيَ اللّٰهُ اَمْرًا كَانَ مَفْعُوْلًا١ۙ۬ لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْۢ بَيِّنَةٍ وَّ يَحْيٰى مَنْ حَيَّ عَنْۢ بَيِّنَةٍ١ؕ وَ اِنَّ اللّٰهَ لَسَمِيْعٌ عَلِيْمٌ (الانفال:۴۳) یعنی ہم اپنے حکم سے تم دونوںکو نکال کر لائے تھے ورنہ نہ وہ آتے نہ تم آتے.اُن کے لئے بھی کوئی جنگ کا موقع نہ تھا کیونکہ اس وقت ان کے مدنظر یہ بات تھی کہ قافلہ اپنےساتھ جو جو چیزیں لایا اسے ہم بیچیں اور روپیہ کمائیں دوسری طرف مسلمانوں کے دلوں میں بھی لڑائی کی کوئی خواہش نہ تھی.یہ اللہ تعالیٰ کا ہی فیصلہ تھا جس نے دونوں کو لڑائی کے لئے جمع کر دیا.فَاِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِؕ۰۰۱۵ چنانچہ وہ یکدم (جنگ کے) میدان میں آموجود ہوں گے.حَلّ لُغَات.اَلسَّاھِرَۃُ السَّاھِرَۃُ قِیْلَ وَجْہُ الْاَرْضِ (مفردات)یعنی سَاھِرَۃ کے معنے سطح زمین کے ہوتے ہیں.اسی طرح اقرب الموارد میں لکھا ہے اَلسَّاھِرَۃُ وَجْہُ الْاَرْضِ.سطح زمین.وَقِیْلَ اَلْفَلَاۃُ.جنگل.(اقرب) تفسیر.فرماتا ہے صرف ایک دفعہ تمہیں ہنکا کر لانے پر کفّار مسلمانوں کے مقابل پر بالکل ننگے ہو جائیں گے اب آگے آگے دیکھنا کیا ہوتا ہے.جب اس ایک واقعہ سے قیامت کے متعلق اُن کے دلوں میں خیالات پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے تو آئندہ کیا ہو گا جب تَتْبَعُھَا الرَّادِفَۃُ کا وقت آئے گا اور پے در پے اُنہیں مسلمانوں کے مقابلہ میں جنگ کے لئے ہنکا کر لایا جائے گا.هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ مُوْسٰىۘ۰۰۱۶اِذْ نَادٰىهُ رَبُّهٗ بِالْوَادِ کیا تجھے موسیٰ کی بات (بھی) پہنچی ہے.جبکہ ااُسے اس کے رب نے ( اس) مقدس وادی الْمُقَدَّسِ طُوًى ۚ۰۰۱۷ یعنی طویٰ میں پکارا.تفسیر.فرماتا ہے جب یہ واقعات ظہور میں آئیں گے تو تم اپنے دل کو تسلی دینے کے لئے کہو گے کہ یہ محض
Page 179
اتفاق ہےحالانکہ تم اسے اتفاق نہیں کہہ سکتے.پہلے نبیوں کے زمانہ میں بھی ایسا ہوتا چلا آیا ہے اور تمہارے سامنے اس کی مثالیں موجود ہیں.تم کس کس شہادت کو اتفاق قرار دے کر اُس کا انکار کرو گے.اوّل تو محمد رسول اللہ صلے اللہ علیہ وآلہٖ وسلم نے تمہارے سامنے صرف یہ پہلی پیشگوئی نہیں کی بلکہ اور بھی کئی پیشگوئیاں کی ہیں اور تم ان نشانات کو پورا ہوتے دیکھ چکے ہو.لیکن اگر پھر بھی تم اس کو اتفاق قرار دو گے تو ہم تمہارے سامنے دوسری مثال پیش کرتے ہیں.آنحضرت ؐ کے غلبہ کے لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات کا ذکر هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ مُوْسٰىکیا تمہیں کچھ موسیٰ کی بھی خبر ہے اِذْ نَادٰىهُ رَبُّهٗ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى جب خدا نے اُس کو طویٰ کی مقدس وادی میں پکارا.طویٰ شام میں ایک وادی بھی ہے اور طُویٰ کے معنے ہیں اَلشَّیْ ئُ الْمُثْنی (اقرب) ایسی چیز جو ٹیڑی ہو سیدھی نہ ہو.حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو دیکھنے اور آنحضرت ؐ کے خدا تعالیٰ کو دیکھنے میں فرق اس آیت میں ایک زبردست لطیفہ ہے اور وُہ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب خدا تعالیٰ سے ملے تو وُہ وادیٔ طویٰ میں تھے جس کے معنے ٹیڑھی وادی کے ہیں لیکن رسول کریم صلے اللہ علیہ وآلہٖ وسلم جب اللہ تعالیٰ سے ملے تو اُس وقت کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں کھینچا ہے کہ دَنَا فَتَدَلّٰى.فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى (النجم :۹،۱۰) آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس طرح جا کھڑے ہوئے جس طرح دو قوسوںمیں وتر ہوتا ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ نزدیک ہو کر آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا.اب یہ سیدھی بات ہے کہ وادیٔ طویٰ میں جو شخص کھڑا ہو گا وہ خدا تعالیٰ کو اُس طرح نہیں دیکھ سکے گا جس طرح قَابَ قَوْسَیْنِوالا دیکھ سکے گا.مثلاً جب یہ شکل بنائی جائے � تو اس میں الفؔ مقام کو بؔ مقام والا نہیں دیکھ سکتا.لیکن اس دوسری شکل میں � مقامِ الفؔ کو بؔ مقام والا دیکھ سکتا ہے.اس میں درحقیقت اس امرکی طرف اشارہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم خدا تعالیٰ کو نہیں دیکھے گی لیکن محمد رسول اللہ صلے اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کے متبع روحانیت میں درجۂ کمال حاصل کریں گے اور وُہ خدا تعالیٰ کو اپنے سامنے دیکھ سکیں گے کیونکہ قَابَ قَوْسَیْنِ والی حالت میں آمنے سامنے ہو کر ایک دوسرے کو دیکھا جا سکتا ہے لیکن دوسری صورت میں آمنے سامنے ہو کر نہیں دیکھا جا سکتا بلکہ خدا ایک زاویہ پر رہتا ہے اور بندہ دوسرے زاویہ پر.
Page 180
اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى ٞۖ۰۰۱۸فَقُلْ هَلْ لَّكَ اِلٰۤى اَنْ (اور فرمایا) فرعون کی طرف جا کیونکہ وہ باغی ہو رہا ہے.اور ( اُسے) کہو کہ کیا تجھے (اس بات کی بھی کچھ) تَزَكّٰى ۙ۰۰۱۹ خواہش ہے کہ تُو پاک ہو جائے.حَلّ لُغَات.تَزَکّٰی تَزَکّٰی اصل میں تَتَزَکّٰی ہے جو تَزَکّٰی سے مضارع مخاطب کا صیغہ ہے اور تَزَکّٰی کے معنے ہیں صَارَزَکِیًّا.پاک ہو گیا (اقرب) اور تَتَزَکّٰی کے معنے ہوں گے.پاک ہوتا ہے.اور ھَلْ لَّکَ اِلٰیٓ اَنْ تَزَکّٰی کے معنے ہوں گے.کیا تیری اس طرف رغبت ہے کہ تُو پاک ہو.تفسیر.خدا تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى تو فرعون کی طرف جا کیونکہ وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے فَقُلْ هَلْ لَّكَ اِلٰۤى اَنْ تَزَكّٰى اور اسے کہہ ارے میاں کچھ پاکیزگی کا بھی دل میں شوق ہے.هَلْ لَّكَ اِلٰۤى اَنْ تَزَكّٰى کے معنی یہ ہیں کہ ھَلْ لَّکَ رَغْبَۃٌ اِلٰی اَنْ تَزَکَّی کیا تزکیہ کی طرف بھی تجھے کچھ رغبت اور شوق ہے.یہ بھی گفتگو کا ایک طریق ہوتا ہے جیسے ہمارے ہندوستان میں عام طور پر کہا جاتا ہے کہ پان کا شوق فرمائیں گے.اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فرعون سے جا کر کہو کہ ارے میاں کچھ پاکیزگی کا بھی شوق ہے؟ اگر تزکیہ کا شوق ہو تو تمہیں کچھ باتیں بتائوں وَاَھْدِیَکَ اِلٰی رَبِّکَ اور میں تجھے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ بتائوں فَتَخْشٰی جس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ خدا کا خوف تمہارے دل میں پیدا ہو جائے گا.وَ اَهْدِيَكَ اِلٰى رَبِّكَ فَتَخْشٰىۚ۰۰۲۰فَاَرٰىهُ الْاٰيَةَالْكُبْرٰى ٞۖ۰۰۲۱ اور (اس کے نتیجہ میں)مَیں تجھے تیرے رب کی طرف راستہ دکھائوںپس تو (خدا سے) ڈرنے لگے چنانچہ (موسیٰ گئے اور انہوں نے) اُسے ایک بڑا نشان دکھلایا.تفسیر.یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن کریم زائد باتیں حذف کر دیتا ہے.پہلے فرمایا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ اگر تمہیں پاکیزگی کا شوق ہو تو میں تمہیں کچھ ہدایت کی باتیں بتلائوں.اس کے بعد
Page 181
یہ مضمون آتا تھا کہ جب فرعون کو یہ کہا گیا تو اُس نے بے رغبتی کا اظہار کیا اور کہا میں ایسی باتوں کی خواہش نہیں رکھتا تم میرے سامنے ایسی باتیں مت پیش کرو.مگر اللہ تعالیٰ نے ان زوائد کو حذف کر دیا.کیونکہ یہ باتیں خود بخود سمجھی جاسکتی ہیں.بہرحال فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان لمبی بحث ہوئی جس کے نتیجہ میں فرعون کو آیت کبریٰ دکھائی گئی.آیت کبریٰ سے مراد معجزہ عصاء یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ کون سی آیت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آیت کبریٰ قرار دیا ہے.نشانات تو بہت سے دکھائے گئے تھے چنانچہ قرآن کریم میں بھی دوسری جگہتِسْعَ اٰيٰتٍۭ بَيِّنٰتٍ (بنی اسرائیل:۱۰۲ ) کے الفاظ آتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے نو نشانات دیئے جو بہت روشن اور واضح تھے.اسی طرح فرماتا ہے وَلَقَدْ اَرَیْنٰہُ اٰیَاتِنَا کُلَّھَا فَکَذَّبَ وَاَبٰی (طٰہٰ:۵۷ ) کہ ہم نے فرعون کو اپنی تمام آیات دکھائیں مگر پھر بھی اُس نے تکذیب کی اور انکار سے کام لیا.پس سوال یہ ہے کہ جب فرعون کو بہت سے نشانات دکھائے گئے تو پھر آیت کُبری سے کون سا نشان مراد ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جیسا کہ سورۂ طٰہٰ سے ہی ظاہر ہے پہلے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا کا معجزہ دکھایا تھا یہاں بھی چونکہ فرعون سے پہلی ملاقات کا ہی ذکر ہے اس لئے آیات کبریٰ سے مراد عصا والا معجزہ ہے.قرآن کریم نے بھی بار بار عصا کے معجزہ کا ذکر کیا ہے.بیشک ید بیضاء کا معجزہ بھی کئی دفعہ ظاہر ہوا مگر بیضاء کا معجزہ ہمیشہ عصا والے معجزہ کے بعد ظاہر ہوا ہے.حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت کے مقام پر کھڑا کیا گیا تو اُس وقت بھی پہلے عصا کا معجزہ ظاہر ہوا اور بعد میں یدِ بیضا کا.فرعون کے سامنے ساحروں کے مقابلہ میں بھی عصا کا معجزہ ہی دکھایا گیا.جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے ساتھ دریا کو پار کیا تو اُس وقت بھی عصا ہی سمندر پر مارا گیا اور جب پانی کی سخت ضرورت تھی تو اُس وقت بھی عصا ہی چٹان پر مارا گیا.پس عصا کے ساتھ خصوصیت سے کئی نشانات وابستہ تھے اِسی لئے اِس معجزہ کو آیت کُبریٰ قرار دیا گیا ہے خروج باب۷ آیت۸ تا۱۰ سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ پہلے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا کا معجزہ ہی دکھایا تھا.چنانچہ لکھا ہےاور خداوند نے موسیٰ اور ہارون کو کہا کہ جب فرعون تمہیں کہے کہ اپنا معجزہ دکھائو تو ہارون کو کہیو کہ اپنا عصا لے اور فرعون کے آگے پھینک دے وہ ایک سانپ بن جائے گا تب موسیٰ اور ہارون فرعون کے آگے گئے اور انہوں نے وہ جو خدا وند نے انہیں فرمایا تھا.کیا.ہارون نے اپنا عصا فرعون اور اس کے خادموں کے آگے پھینکا اور وہ سانپ ہوگیا.قرآن کریم کے رُو سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ میں ساحروں نے بھی یہی معجزہ دکھانا چاہا تھا جس
Page 182
سے معلوم ہوتا ہے کہ دشمن بھی اس معجزہ کی اہمیت کو تسلیم کرتا تھا.بائیبل نے بیان کیا ہے کہ خون بنانے کا معجزہ بھی ساحروں نے دکھایا مگر قرآن کریم نے اس کا ذکر چھوڑ دیا ہے.اصل معجزہ جو فرعون اور اس کے ساتھیوں کو دکھایا گیا عصا کا ہی تھا باقی جس قدر معجزات تھے وہ اس کے تابع تھے.فَكَذَّبَ وَعَصٰىٞۖ۰۰۲۲ثُمَّ اَدْبَرَ يَسْعٰى ٞۖ۰۰۲۳ جس پر اس نے (موسیٰ کو) جھٹلایا اور نافرمانی کی.مزید براں (اُس نے) فساد کی تدبیریں کرتے ہوئے حق سے فَحَشَرَ فَنَادٰى ٞۖ۰۰۲۴فَقَالَ اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلٰى ٞۖ۰۰۲۵ پیٹھ پھیر لی چنانچہ (اس نے درباریوں کو) جمع کیا اور (ملک میں عام) منادی (بھی) کرائی اور (لوگوں کو جمع کر کے) کہا کہ میں تمہاراسب سے بڑا رب ہوں.تفسیر.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے باوجود اس کے کہ فرعون کو آیت کبریٰ دکھائی گئی پھر بھی اُس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا اور نافرمانی کی.ثُمَّ اَدْبَرَ پھر پیٹھ پھیری.یَسْعٰی اور مخالفت میں لگ گیا.یَسْعٰی کے معنے سعی اور کوشش کے بھی ہوتے ہیں اور دروڑنے کے بھی.یہاں یَسْعٰی سے مراد عملی کوشش کے ہیں نہ کہ قدموں سے بھاگنے کی کوشش کے.اور مطلب یہ ہے کہ اُس نے پورا زور مخالفت میں لگایا اور اپنی تمام کوششیں موسیٰ ؑ کو برباد کرنے میں صرف کر دیں.فَحَشَرَ فَنَادٰىمیں عوام اور خواص ہر دو قسم کے لوگوں کو بلانے کی طرف اشارہ فَحَشَرَ فَنَادٰی پھر اس نے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا.اور اُنہیں بلانے کے لئے منادی کی.اکٹھا کرنے سے یہ مراد ہے کہ اُس کی طرف سے بڑے بڑے لوگوں کو چٹھیاں بھیجی گئیں کہ وہ فلاں دن جمع ہو جائیں.دُنیا میں بُلانے کے دو ہی طریق ہیں.معزز لوگوں کی طرف چٹھیاں بھیج دی جاتی ہیں اور عوام کو بُلانے کے لئے منادی کر دی جاتی ہے.اُس نے بھی بڑے بڑے اُمراء اور سرداروں کو خاص طور پر چٹھیاں بھجوا دیں یا اُن کی طرف آدمی بھیج دئے کہ وہ فلاں دن پہنچ جائیں.اور پھر عام منادی بھی کرا دی تاکہ سب لوگ جمع ہو جائیں.جب سب لوگ اکٹھے ہوگئے تو وہ اُن سے کہنے لگا اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلٰى میں تمہارا بڑا رب ہوں مگر یہ شخص تمہارے خلاف منصوبہ بازیاں کرتا رہتا ہے تم سب کو اس کے خلاف اکٹھے ہو جانا چاہیے.
Page 183
فَاَخَذَهُ اللّٰهُ نَكَالَ الْاٰخِرَةِ وَ الْاُوْلٰى ؕ۰۰۲۶ اس پر اللہ (تعالیٰ) نے اسے آخرت اور دنیا کے عذاب میں مبتلا کرنے کے لئے پکڑ لیا.حَلّ لُغَات.نَکَال نَکَالٌ نَکَلَ سے اسم ہے اور نَکَلَ بِفُلَانٍ کے معنے ہیں صَنَعَ بِہٖ صَنِیْعًا یَحْذُرُ غَیْرَہُ اِذَارَاٰہُ کسی امر کے مرتکب ہونے پر کسی سے ایسا سلوک کیا کہ دوسرا شخص اس سلوک کو دیکھ کر عبرت پکڑے اور وہ ویسے کام کا مرتکب نہ ہو (اقرب) پس اِلنَّکَالُ کے معنے ہیں ایسی سزا جو عبرت دلا دے.تفسیر.اللہ تعالیٰ نے اُس کو موسیٰ ؑ کی پیشگوئی کے ماتحت نکالِ آخرت کے ذریعہ سے تباہ کر دیا.یہاں نَکَالَ الْاٰخِرَۃِ یا تومفعول لہٗ ہے اوریا مفعول مطلق ہے کیونکہ نَکَلَ بِہٖ کے معنےبھی اَخَذَہٗ کے ہی ہوتے ہیں.پس اس کے یا تو یہ معنے ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اُس کو عذابِ آخرت اور عذابِ اُولیٰ میں مبتلا کرنے کے لئے پکڑایا بُری طرح پکڑا.آخرت کے لحاظ سے بھی اور اُولیٰ کے لحاظ سے بھی.یہاں بھی وہی نتیجہ نکالا گیا ہے جو اسلامی غلبہ کی پیشگوئی سے نکالا گیا تھا کہ موسیٰ ؑ کی جیت سے نہ صرف وہ پیشگوئی پوری ہو گئی جو موسیٰ ؑ کے غلبہ کے متعلق تھی بلکہ اس پیشگوئی کے ظہور سے قیامت کا ثبوت بھی مل گیا کیونکہ یہ دونوں پیشگوئیاں آپس میں وابستہ و پیوستہ تھیں جب ایک ناممکن بات مخالف حالات کے باوجود پوری ہو گئی تو اس سے نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ دوسری بات بھی ایک دن پوری ہو جائے گی.درحقیقت ہر نبی جو اس دنیا میں آیا ہے اُس کا خدا تعالیٰ پر ایمان پیدا کرنے کے بعد مقدّم کام یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگو ں کے دلوں میں قیامت کے متعلق ایمان اور یقین پیدا کرے.یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے غلبہ اور اپنی کامیابی کی پیشگوئی کو قیامت کے ساتھ جوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مخالف حالات کے باوجود ایک دن تم پر غالب آئوں گا اور میرا یہ غلبہ اس بات کا ثبوت ہو گا کہ قیامت کے متعلق میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ بھی ایک دن پورا ہو جائے گا کیونکہ میرا کام مُردہ روحوں کو زندہ کرنا ہے جو بظاہر حالات بالکل ناممکن دکھائی دیتا ہے اگر یہ زندگی ایک دن پیدا ہو گئی اگر یہ رُوحانی مردے ایک دن زندہ ہو گئے اور اگر یہ ناممکن حالات ایک دن ممکن نظر آنے لگے تو تمہیں یقین کر لینا چاہیے کہ اگلے جہان کی زندگی کے متعلق جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ بھی بالکل صحیح اور درست ہے.کیونکہ اگر مردہ روحیں اس جہان میں زندہ ہو سکتی ہیں تو اگلے جہان میں بھی مردے زندہ ہو سکتے ہیں.اس نظارہ کو دیکھنے کے بعد قیامت پر یقین لانا بالکل آسان ہو جاتا ہے اور ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ جس خدا کی قدرت میں یہ بات داخل ہے کہ وہ اس جہان میں
Page 184
بعث روحانی کر دے وہ اگلے جہان میں بھی مردہ کو زندہ کر سکتا ہے.فرعون کا موسیٰ علیہ السلام کے مقابل اس دنیا میں عذاب میں گرفتار ہونا اس کے آخرت میں عذاب میں مبتلا ہونے کی ایک دلیل پس فرماتا ہے فَاَخَذَهُ اللّٰهُ نَكَالَ الْاٰخِرَةِ وَ الْاُوْلٰى.اللہ تعالیٰ نے اُس کو آخرت کے عذاب سے بھی پکڑا اور دنیا کے عذاب سے بھی پکڑا یہاں خدا تعالیٰ نے یَاْخُذُہُ اللہُ نَکَالَ الْاٰخِرَۃِ نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو آخرت کے عذاب سے پکڑے گا بلکہ اَخَذَہُ اللّٰہُ فرمایا یعنی اللہ تعالیٰ نے اُسے نکالِ آخرۃ دینے کے لئے پکڑا جس کے معنے درحقیقت یہی ہیں کہ اس عذابِ اُولیٰ نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ مرنے کے بعد زندہ بھی ہو گا اور اُسے آخرت کا عذاب بھی دیا جائے گا.ماضی کے لفظ سے قیامت کی موجودگی کی دلیل بیان کی گئی ہے اسی لئے آخرۃ کو پہلے رکھا اور اولیٰ کو بعد میں رکھا جس میں یہی اشارہ ہے کہ اس عذاب اُولیٰ نے ثابت کر دیا ہے کہ فرعون زندہ بھی ہو گا اور اُسے عذابِ آخرت میں بھی گرفتار کیا جائے گا.گویا بتایا کہ محمدصلے اللہ علیہ وسلم کے غلبہ کی یہ پہلی مثال نہیں کہ تم اسے اتفاق قرار دے دو بلکہ ہمیشہ سے ایسا ہوتا چلا آیا ہے.جب بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی نبی آیا ہے ناممکن حالات میں اُس نے غلبہ حاصل کیا ہے غلبہ کے سامان اُسے حاصل نہیں ہوتے.طاقت اُس کے پاس نہیں ہوتی.مال اُس کے پاس نہیں ہوتا.جمعیت اس کے پاس نہیں ہوتی مگر پھر بھی خدا تعالیٰ اُسے غالب کر دیتا ہے اور اُس کے ہاتھ سے قوموں کا احیا ءکر تا ہے.یہ دلیل ہوتی ہے اس بات کی کہ جب مخالف حالات میں اِس جگہ روحانی احیاء ہو گیا تو موت کے بعد بھی اِحیاء ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ سب کو زندہ کر دے گا.جس خدا نے مردہ دلوں اور مردہ روحوں کو اس جہان میں ناممکن حالات میں زندہ کر دیا کیا وہ خدا یہ طاقت نہیں رکھتا کہ مردہ جسموں کوبظاہر ناممکن حالات میں زندہ کر دے.یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے جو آج کل کے مفکّر کیا کرتے ہیں اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ سوال نہایت اہم ہے.وہ سوال یہ کیا کرتے ہیں کہ کسی ایک چیز سے دوسری چیز کا نتیجہ نکال لینا منطقی طور پر درست نہیں ہے.اگر ہم کسی کے متعلق یہ کہیں کہ وہ بہت بڑا عالم ہے تو کیا اس سے یہ نتیجہ نکل آئے گا کہ وہ کرسی بھی بنا سکتا ہے یا کُوچ بھی تیار کر سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں اگر تم ثابت بھی کر دو کہ خدا تعالیٰ نے بعض غیب کی خبریں دیں اور وہ پوری ہو گئیں تو اس سے اتنا ہی نتیجہ نکلے گا کہ جو خبریں دی گئی تھیں وہ پوری ہو گئیں یہ کس طرح نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ قیامت بھی آجائے گی اِن دوباتوں کا تو آپس میں کوئی جوڑ اور تعلق ہی نہیں.اُن کی یہ دلیل واقعہ میں اہم ہے اور جس حد تک وہ بات بیان کرتے ہیں اُس حد تک ہمیں اُس کی صحت تسلیم کرنے سے کوئی انکار نہیں.ہم بھی تسلیم کرتے ہیں کسی ایک صفت
Page 185
سے دوسری صفت کا نتیجہ نہیں نکالا جا سکتا جب تک وہ دونوں آپس میں لازم وملزوم نہ ہوں یا سابق مسبوق کی حیثیت اُن میں نہ پائی جاتی ہو یا سبب اور مسبب کے طور پر وہ دونوں اکٹھی نہ ہوں یعنی یا تو یہ ہو کہ جہاں ایک بات پائی جاتی ہو وہاں لازمًا دوسری بات بھی پائی جانی چاہیے تب بے شک ایک بات کو دوسری بات کے ثبوت کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے اور یا پھر دونوں باتیں آپس میں ایسی مشابہ ہوں کہ ایک بات کی موجودگی دوسری بات کا یقین دلانے کے لئے بالکل کافی ہو.مثلاً یہ کہنا کہ جب ایک شخـص عالم ہے تو وہ کُرسی بھی بنا سکتا ہے یا کُوچ بھی تیار کر سکتا ہے بیشک بے وقوفی ہے کیونکہ ان دونوں باتوںمیں ایسی کوئی نسبت نہیں پائی جاتی.لیکن اگر ایک شخص ہم کو ایک انگریزی کتاب پڑھ کر سنائے اور ہم اس کے متعلق کہہ دیں کہ وہ دوسری انگریزی کتاب بھی پڑھ سکتا ہے اور وہ آگے سے کہہ دے کہ تم یہ نتیجہ کس طرح نکال سکتے ہو تو سب لوگ ہنس پڑیں گے کہ جب اُس نے ایک انگریزی کتا ب کو پڑھ لیا تو اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ وہ دوسری کتاب بھی پڑھ سکے گا بالکل درست اور طبعی نتیجہ ہے اس میں خلاف عقل کون سی بات ہے یا اگر کوئی شخص اردو کی کوئی کتاب پڑھ سکتا ہے اور ہم اس کے متعلق کہہ دیتے ہیں کہ وہ دوسری کتاب بھی جو اردو میں ہے پڑھ سکتا ہے تو یہ بالکل جائز ہو گا کیونکہ دونوں چیزوں میں آپس میں ایسی مشابہت پائی جاتی ہے کہ ایک بات کی موجودگی کی وجہ سے دوسری بات کا انکار ہی نہیں ہو سکتا.قیامت کے ثبوت کے لئے تین ثبوت اب ہم دیکھتے ہیں کہ قیامت کے مشابہ کون کون سی چیز ہے.قیامت کے لئے پہلی اور دوسری دلیل یعنی خدا تعالیٰ کی صفت خلق سو اس بارہ میں سب سے پہلی چیز جو قیامت سے مشابہت رکھتی ہے صفتِ خلق ہے اگر یہ ثابت ہو جائے کہ خدا تعالیٰ خلق کرتا ہے خواہ اُس نے سابق میں خلق کیا ہو یا اب خلق کیا ہو تو بہرحال یہ ماننا پڑے گا کہ جو ہستی ایک دفعہ خلق کر سکتی ہے وہ دوسری دفعہ بھی کر سکتی ہے.سوال صرف یہ رہ جائے گا کہ آیا اُس نے کہا بھی ہے یا نہیں کہ میں دوبارہ خلق کروں گا.اگر اُس نے کہہ دیا ہو کہ میں دوبارہ بھی خلق کروں گا تو بات ختم ہو جاتی ہے اور ماننا پڑتا ہے کہ جو خدا ایک دفعہ پیدا کر سکتا ہے وہ دوسری دفعہ بھی پیدا کر سکتا ہے.پس اگر ہم ثابت کر دیں کہ خدا تعالیٰ اس جہان میں خلق کرتا ہے تو چونکہ خلق قیامت کے مشابہ چیز ہے اس لئے یہ دلیل اس بات کو ثابت کر دے گی کہ قیامت کا عقیدہ بھی درست ہے.دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس خلق کے مشا بہ کوئی اور خلق ہو جو ویسی ہی مستبعد اور تعجب انگیز ہو جیسے یہ خلق مستبعد اور تعجب انگیز ہے تو جو خدا اس خلق کے مشابہ خلق کر سکے گا اس کے متعلق ہمیں ماننا پڑے گا کہ اگر وہ دعویٰ کرے تو وہ قیامت کے دن بھی ایک نئی خلق پر قدرت رکھتا ہے کیونکہ اُس نے دکھا دیا کہ وہ ویسی ہی خلق اس دنیا میں کر سکتا ہے
Page 186
اور جب اُس نے اپنی قدرت اور طاقت اور جلال کا ثبوت اِسی دنیا میں اُس خلق کے مشابہ ایک اَور خلق سے دے دیا ہے تو ہمیں ایمان لانا پڑے گا کہ اتنی بڑی طاقت رکھنے والے خدا نے جب کہا ہے کہ میں اگلے جہان میں بھی ایک خلق کروں تو ضرور اُس نے سچ کہا ہے اتنی بڑی طاقت اور قوت رکھنے کے بعد اُسے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی.قیامت کے ثبوت کے لئے تیسری دلیل یعنی خدا تعالیٰ کا علم تام تیسری چیز علم تام ہے.اگر ثابت ہو جائے کہ خدا تعالیٰ کو علم تام حاصل ہے تب بھی مسئلہ بالکل حل ہو جائے گا کیونکہ جو ہستی کسی چیز کے متعلق علم تام رکھتی ہو وہ اسے ہر وقت بنا سکتی ہے.حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنی کتب میں تحریر فرمایا ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں خدا تعالیٰ نے دنیا کس طرح بنائی ہے؟آپ فرماتے ہیں اگر تمہیں دنیا کی پیدائش کے متعلق علم تام حاصل ہو جائے تو پھر تم میں اور خدا میں فرق کیارہ جائے.پھر تم بھی آسمان اورزمین اور چاند اور سورج اور ستارے بنانے لگ جاؤ.جس شخص کو پتہ ہو کہ میز اس طرح بنتا ہے کرسی اس طرح تیار ہوتی ہے.ہتھوڑا اس طرح چلایا جاتا ہے.تیشے کا اس طرح استعمال کیا جاتا ہے.وہ بہرحال میز اور کرسی کو بنا لے گا اور اس کے لئے یہ کام کرنا کوئی مشکل نہیں ہو گا.(سرمہ چشمہ آریہ روحانی خزائن جلد ۲ صفحہ ۲۲۹،۲۶۳،۲۶۹)پس اگر یہ ثابت ہو جائے کہ خدا تعالیٰ کو مخلوق کے متعلق علم تام حاصل ہے تو اس کے بعد یہ کہنا کہ وہ دوبارہ لوگوں کو زندہ نہیں کر سکتا یا دوبارہ ان کو پیدا نہیں کر سکتا ایک پاگل پن کی بات ہوگی.یہ تین چیزیں ہیں جو قیامت کے ثبوت کے لئے ضروری ہیں اور یہ تینوں چیز یں مل کر قیامت کا ثبوت بنتی ہیں.یعنی یا تو یہ ثابت ہو جائے کہ دنیا میں جس قدر مخلوق ہے سب خدا تعالیٰ نے پیدا کی ہے تو پھر اس سے یہ نتیجہ نکالا جا سکے گا کہ جو خدا اس جہان میں پیدا کر سکتا ہے وہ اگلے جہان میں بھی پیدا کر سکتا ہے.اور یا پھر یہ ثابت ہو جائے کہ وہ اسی قسم کا مشابہ احیاء اس دنیا میں بھی کیا کرتا ہے.جب یہ ثابت ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ایک قسم کا احیاء اس دنیا میں بھی کیا کرتا ہے تو اگلے جہان کے متعلق بھی یہ تسلیم کرنا بڑے گا کہ وہاں اللہ تعالیٰ احیاء کر سکتا ہے اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ خدا تعالیٰ کو مخلوق کے متعلق علم تام حاصل ہے تو اس کے بعد بھی قیامت پر ایمان لانا پڑے گا.کیونکہ جسے مخلوق کا علم تام حاصل ہو.جو اس کی جزئیات تک سے واقف ہو.جو اس کی باریکیوں سے آگاہ ہو وہ یقیناً دوبارہ بھی مخلوق کوپیدا کر سکتا ہے.یہ تین چیزیں ہیں جو مل کر قیامت کاثبوت بنتی ہیں.اور یہی تینوں چیزیں قرآن کریم میں ہمیشہ اکٹھی پیش کی جاتی ہیں تا کہ قیامت کا انکار نہ ہو سکے.ہم یہ نہیں کہتے کہ چونکہ خدا تعالیٰ نے فلاں بات کہی تھی اور وہ بات پوری ہو گئی اس لئے قیامت بھی آجائے گی.اگر صرف اتنی بات کہی جائے تو ہم تسلیم کرتے ہیں کہ یہ دلیل نا کافی ہو گی.یا
Page 187
اگر یہ کہا جائے کہ چونکہ پیشگوئی کے مطابق فلاں مقدمیں فتح ہو گئی یا فلاں شخص کےگھر لڑکا پیدا ہو گیا اس لئے یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ قیامت بھی ہو گی تو تسلیم کریں گے کہ یہ قیامت کی کوئی دلیل نہیں اور یقیناً زید کے گھر لڑکا ہونے یا کسی مقد مہ میں کامیابی حاصل ہو جانے کا منطقی طور پر یہ نتیجہ نہیں نکل سکتا ہے کہ قیامت بھی آنیوالی ہے کیونکہ یہ باتیں آپس میں لازم ملزوم نہیں ہیں اور نہ اِن کا قیامت سے کوئی براہ راست تعلق ہے.ہم جو کچھ کہتے ہیں وہ تو بالکل اور ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا ہے اور جو خدا ایک دفعہ پیدا کر سکتا ہے وہ دوسری دفعہ بھی پیدا کر سکتا ہے.ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس احیاء کے بالکل مشا بہ اس دنیا میں ایک روحانی احیاء بھی کیا کرتا ہے پس جو خدا ایک مشابہ خلق کر سکتا ہے وہ اگلے جہان میں بھی نئی خلق پر قدرت رکھتا ہے.پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو علمِ تام حاصل ہے اور مخلوق کے تمام اسرار کو وہ جانتا ہے.اور جب یہ کیفیت ہے تو مخلوق کاپیدا کرنا اس کے لئے کون سا مشکل کام ہے.قرآن کریم نے قیامت کے ثبوت میں یہی طریق اختیار کیا ہے.بے شک دوسری کتابوں پر یہ اعتراض وارد ہو سکتا ہے کہ وہ قیامت کا ثبوت پیش نہیں کرتیں مگر قرآن کریم پر یہ اعتراض نہیں ہو سکتا.قرآن کریم جہاں بھی قیامت کا ذکر کرتا ہے وہاں پہلی خلق کو اس کے ثبوت کے طور پر پیش کرتا ہے چنانچہ سورۂ یٓس میں ہی جب اس سوال کا ذکر کیا گیا کہ مَنْ یُّحْیِ الْعِظَامَ وَھِیَ رَمِیْمٌ تو اس کا جواب یہ دیاگیا کہ قُلْ يُحْيِيْهَا الَّذِيْۤ اَنْشَاَهَاۤ اَوَّلَ مَرَّةٍ١ؕ وَ هُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيْمُ.ا۟لَّذِيْ جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الشَّجَرِ الْاَخْضَرِ نَارًا فَاِذَاۤ اَنْتُمْ مِّنْهُ تُوْقِدُوْنَ.اَوَ لَيْسَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ بِقٰدِرٍ عَلٰۤى اَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ١ؐؕ بَلٰى ١ۗ وَ هُوَ الْخَلّٰقُ الْعَلِيْمُ(یٰس :۷۹ تا ۸۲)یہاں بھی پہلی خلق اور علمِ تام سے قیامت کانتیجہ نکالا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ جو خدا ایک دفعہ پیدا کر سکتا ہے اور کل علم مخلوق کا رکھتا ہے کیا اُس کی طاقت اور قدرت میں یہ بات نہیں کہ وہ دوبارہ بھی پیدا کر دے.گویا قیامت کی ایک دلیل اللہ تعالیٰ یہ دیتا ہے کہ وہ کہتا ہے تمہاری آنکھوں کے سامنے مخلوق موجود ہے تم بتائو یہ کس نے پیدا کی ہے.جب خدا نے اس تمام مخلوق کو پیدا کیا ہے توتم کس طرح کہہ سکتے ہو کہ وہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا.قیامت کی دوسری دلیل کے طور پر اللہ تعالیٰ اُس نشاۃ روحانیہ کو پیش کرتا ہے جو انبیاء کے ذریعہ اس دنیا میں ہوتی ہے اور بتاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ مخالف بلکہ ناممکن قرار دینے والے حالات میں مُردہ روحوں کو اس دُنیا میں زندہ کر دیتا ہے تو تم کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ اگلے جہان میں بھی وہ زندگی بخش سکتا ہے.اُس کے لئے یہ کام ناممکن نہیں ہے.تیسری دلیل علم کامل کی ہے.علم کامل کے بعد بھی کسی چیز کا بنانا کوئی مشکل امر نہیں رہتا.جس شخص کو پتہ ہو کہ
Page 188
حلوا اس طرح بنتا ہے کہ پہلے سُوجی لی جائے پھر اُسے گھی میں بُھونا جائے پھر اُس میں میٹھا ملایا جائے اور پانی میں ملا کر آگ پر اُسے دم دیا جائے وہ جب چاہے گا حلوا بنا لے گا اُسے کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی.اِسی طرح جب خدا تعالیٰ کو مخلوق کے متعلق علمِ تام حاصل ہے اور وہ کائنات کے تمام اسرار جانتا ہے تو اس کے لئے مردوں کو زندہ کر دینا کون سا مشکل کام ہے جس نے یہ کام ایک دفعہ کر لیا وہ اُسے دوسری دفعہ بھی کرلے گا.غرض یہ تین دلیلیں ہیں جو اللہ تعالیٰ قیامت کے ثبوت میں دیا کرتا ہے اس لئے لوگوں کا یہ اعتراض کرنا کہ ایک غیب کی خبر پوری ہونے سے دوسری خبر کی صداقت کا ہم کس طرح نتیجہ نکال سکتے ہیں صحیح نہیں.اگر صرف ایک غیب کی خبر سے دوسری غیب کی خبر کو سچّا قرار دیا جاتا تو بے شک یہ اعتراض ہو سکتا مگر ہمارا تو یہ دعویٰ ہی نہیں.ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا خلق پر قادر ہونا.اُس کا اِسی دنیا میں اِحیاء موتیٰ کر دینا اور پھر مخلوق کے متعلق علمِ تام رکھنا یہ قیامت کی دلیل ہے.ہم یہ نہیں کہتے کہ چونکہ لیکھرام پیشگوئی کے مطابق مر گیا اس لئے یہ ثبوت ہو گا اس کا بات کا کہ قیامت بھی آنےوالی ہے.یا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے فلاں بیٹے کے متعلق پیشگوئی کی تھی اور وہ پوری ہو گئی ہے اِس لئے یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ قیامت بھی آنے والی ہے.ہم قیامت کے ثبوت میں اِن تین باتوں کو پیش کرتے ہیں جن کو تفصیل کے ساتھ میں بیان کر چکا ہوں.اِن پیشگوئیوں کے پورا ہونے سے اللہ تعالیٰ کا صرف جزئیات کے متعلق علم ثابت ہوتا ہے علمِ کامل ثابت نہیں ہوتا.لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب اِحیاء موتیٰ کی صفت ظاہر ہو تو وہ بے شک قیامت کا ثبوت ہوتی ہے کیونکہ لوگوں کے سامنے ایک نمونہ موجود ہوتا ہے کہ مردہ روحیں نبی کے فیضِ صحبت اور اُس کی قوتِ قدسیہ سے زندہ ہو گئیں اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس خدا نے اس دنیا میں مردہ روحوں کو زندہ کر دیا ہے وہ اگلے جہان میں بھی زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے.یا پھر دوسری دلیل خلق ؔکی ہے جو خدا ایک دفعہ مخلوق کو پیدا کر سکتا ہے اس کے لئے یہ کون سی مشکل بات ہے کہ وہ دوبارہ اُسی مخلوق کو پیدا کر دے.تیسری چیز عِلمؔ کامل ہے.جس خدا کو تمام کائنات کا علمِ تام حاصل ہے اور وہ کائنات کے اسرار کو جانتا ہے اس کے لئے بھی مخلوق کا دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں.غرض یہ تین دلیلیں ہیں جو قرآن کریم قیامت کے ثبوت کے طور پر پیش کرتا ہے اور جن کو کوئی شخص ردّ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا.پس بے شک آج کل تعلیم یافتہ طبقہ کی طرف سے جو سوال کیا جاتا ہے وہ درست ہے مگر جہاں تک اُن کا یہ خیال ہے کہ قرآن کریم نے بھی اسی رنگ کو اختیار کیا ہے وہ غلط ہے.ہم اس بات سے کلیۃً متفق ہیں کہ بعض پیشگوئیاں یقیناً ایسی ہوتی ہیں جن کو قیامت کے ثبوت کے طور پر پیش نہیںکیا جا سکتا.لیکن ہم اس امر کے اظہار سے بھی نہیں رہ سکتے کہ جہاں یہ تین باتیں مل جائیں یا ان تین باتوں
Page 189
میں سے کوئی ایک بات ہی بیان کر دی جائے وہاں یقینی اور قطعی طور پر یہ قیامت کی دلیل بن جاتی ہیں کیونکہ یہ تینوں دلیلیں ایسی ہیں جو قیامت کے ساتھ لازم ملزوم کی حیثیت رکھتی ہیں.ان میں سے جو بات بھی ثابت ہو جائے وہ قیامت کو ضرور ثابت کر دے گی.پس یہ اعتراض جو آجکل کے مفکرین کی طرف سے کیا جاتا ہے بالکل غلط ہے اور قرآن کریم کی حقیقت کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے.اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَنْ يَّخْشٰى ٢ؕؒ۰۰۲۷ یقیناً اس (واقعہ) میں اس کے لئے جو خدا سے ڈرتا ہے ایک بڑی عبرت (کا سامان) ہے حل لغات.اَلْعِبْرَۃُ اَلْعِبْرَۃُکے معنے ہیں (۱) اَلْاَصْلُ الَّذِیْ تُرَدُّ اِلَیْہِ النَّظَائِرُ.ایسا اصل جس کی طرف اس کے امثال کو لوٹا کر ان کی حقیقت و اصلیت معلوم کی جا سکے (۲) اَلنَّظْرُ فِیْ الْاَحْوَالِ حالات میں غور وفکر کر کے اُن کی حقیقت کو پانا (۳)اَلْعِظَۃُ یُتَّعَظُ بِھَا ایسی بات جس سے نصیحت حاصل کی جا سکے (اقرب) اس کی جمع عِبَرٌ آتی ہے.تفسیر.عبرة سے مراد عبرت سے مراد یہ ہے کہ اِس سے اُخروی زندگی کی دلیل دی جا سکتی ہے.ایک نہیں متعدد مثالیں ایسی پائی جاتی ہیں کہ اُخروی زندگی کو دنیوی روحانی اِحیاء سے ملا کر خدا تعالیٰ کے انبیاء نے پیش کیا ہے اور ناممکن حالات میں اِحیاء کر کے اُخروی زندگی کا ثبوت دیا ہے پس اگر کوئی شخص خدا تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں رکھتا ہو اور ضد اور تعصّب کا مادہ اُس میں نہ ہو تو وہ اِس سے اُخروی زندگی پر یقین اور ایمان اپنے دل میں پیدا کر سکتا ہے.عِبْرَۃٌ عَبُوْرٌ سے نکلا ہے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کو کہتے ہیں.پس عِبْرَۃٌ کے معنے ہوتے ہیں ایک بات سے دوسری کا نتیجہ نکالنا.گویا وہ پُل کی طرح ایک طرف سے دوسری طرف عبور کا سامان کر دیتی ہے.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ دلیل بھی ایسی ہے جو انسانی دماغ کو ضرور اس طرف لے جاتی ہے کہ مرنے کے بعد بھی ایک قیامت ہونے والی ہے.ءَاَنْتُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمِ السَّمَآءُ١ؕ بَنٰىهَاٙ۰۰۲۸ کیا تمہیں پیدا کرنا زیادہ دشوار ہے یا آسمان کو جسے اس (خدا) نے بنایا ہے.تفسیر.فرماتا ہے کیا تمہاری پیدائش زیادہ مشکل اور سخت ہے اَمِ السَّمَآءُ بَنٰـھَایا آسمان و زمین کی
Page 190
پیدائش زیادہ مشکل ہے.اَمِ السَّمَآءُ بَنٰىهَامیں السماء سے مراد اجرام فلکی یہاں اَشَدُّ خَلْقًا اَمِ السَّمَآءُ١ؕ بَنٰىهَا سے مراد صرف آسمان ہی نہیں جیسا کہ اگلی آیات سے ظاہر ہے کہ ایک طرف تو اَشَدُّ خَلْقًا اَمِ السَّمَآءُ١ؕ بَنٰىهَا کہا اور دوسری طرف تشریح کرتے ہوئے اس میں زمین کو بھی شامل کر لیا.پس درحقیقت یہاں سماء سے مراد نظامِ سماوی ہے اور اس کی پیدائش کی اہمیت کو اس طرح بیان فرمایا ہے کہ رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوّٰىهَا.وَ اَغْطَشَ لَيْلَهَا وَ اَخْرَجَ ضُحٰىهَا.وَ الْاَرْضَ بَعْدَ ذٰلِكَ دَحٰىهَا.اَخْرَجَ مِنْهَا مَآءَهَا وَ مَرْعٰىهَا.وَ الْجِبَالَ اَرْسٰىهَا.مَتَاعًا لَّكُمْ وَ لِاَنْعَامِكُمْ گویا جو تشریح کی گئی ہے اُس میں اجرام فلکی.بلندی.جَواور زمین وغیرہ سب شامل ہیں.پس یہاں سماء سے مراد نظامِ سماوی ہے خالی وہ سماء مراد نہیں جو زمین کے مقابلہ میں ہوتا ہے بلکہ وہ سماء مراد ہے جس میں زمین بھی شامل ہے.فرماتا ہے کہ کارخانۂ عالم جس کا ہم اب ذکر کرنے والے ہیں تم سے بہت زیادہ اہم اور پیچیدہ ہے.انسان درحقیقت اپنے متعلق دھوکا کھا جاتا ہے اور وہ یہ کہ بظاہر وہ یہ خیال کرتا ہے کہ نظامِ عالم اور انسان کو آپس میں مشابہ کس طرح قرار دیا جا سکتا ہے اور ان میں ایک دوسرے کی دلیل کس طرح بن سکتا ہے.انسان تو بڑا عقلمند.سمجھدار اور غور و فکر کا ملکہ اپنے اندر رکھنے والا ہے اور سورج چاند وغیرہ میں کوئی سوچ سمجھ نہیں.اس طرح وہ خیال کرتا ہے کہ یہ دلیل ایسی دلیل ہے جس میں ایک ادنیٰ چیز کو اعلیٰ چیز سے مشابہت دی جاتی ہے او رادنیٰ چیز کو ثابت کر کے اعلیٰ چیز کے وجود کا استدلال کیا جاتا ہے مگر یہ غلط ہے درحقیقت پیدائشِ عالم کے سلسلہ سے استدلال اعلیٰ سے ادنیٰ کا استدلال ہے نہ کہ ادنیٰ سے اعلیٰ کا استدلال.اس میں استدلال بالاولیٰ ہے.بات یہ ہے کہ انسان کو اپنی ذات کے متعلق یہ دھوکا لگ جاتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے میں بڑا سوچنے والا اور سمجھنے والا اور تدبر کرنے والا انسان ہوں اس لئے اپنی ذات کی ابتداء کی طرف اُس کا ذہن نہیں جاتا.انسان اپنے آپ کو مکمل سمجھتا اور دنیا میں خدا تعالیٰ کا قائم مقام سمجھتا ہے اِس لئے سبب اور مسبب کی جو دلیل ہے اس کی طرف اپنی پیدائش کو مدنظر رکھتے ہوئے اس کا ذہن نہیں جاتا.اِس وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیشہ نظامِ عالم کو اپنی ہستی کے ثبوت میں پیش کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ دیکھو کیا تمہیں اس عظیم الشان نظام سے یہ نظر نہیں آتا کہ اس میں ایک خالق کا ہاتھ کام کر رہا ہے اور ہر ٹکڑہ دوسرے ٹکڑے کا محتا ج ہے کوئی چیز اپنی ذات میں منفرد نہیں ہے.سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ دنیا اس طرح بنی ہے کہ ذرّے آپس میں جُڑ گئے اور اُن ذرّوں کے آپس میں ملنے سے آہستہ آہستہ یہ عظیم الشان دنیا تیار ہو گئی.لیکن سوال یہ ہے کہ ہم نے مان لیا دنیا مختلف ذرّات کے مجموعہ سے بنی ہے مگر اُن ذرّوں کے آپس میں ملنے سے یہ کس طرح ہو گیا کہ ہمیں آج یہاں
Page 191
ضرورت پیش آتی ہے تو میلوں میل پر اُس ضرورت کو پورا کرنے کا سامان موجود ہوتا ہے بیشک ہم تسلیم کرلیتے ہیں کہ ایٹمز ATOMS کے ملنے سے یہ دنیا بنی لیکن اگر اس دنیا کا کوئی خدا نہیں تو یہ کس طرح ہو گیا کہ وہ ذرّے اسی طرح آپس میں ملے جس طرح بنی نوع انسان کو ضرورت تھی اور اسی جگہ ملے جہاں انسان کو کوئی ضرورت پیش آنے والی تھی.ذرّوں کا آپس میں ملنا اتفاق ہو سکتا ہے لیکن اُن ذرّوں کا آپس میں مل کر ہر انسانی ضرورت کو پورا کرنے کا سامان مہیا کر دینا یہ اتفاق نہیں ہو سکتا بلکہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ اس کارخانۂ عالم کے پیچھے کوئی اور ہستی کام کر رہی ہے.ہم اگر ایک چمڑا پڑا ہوا دیکھیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ چمڑا یہاں اتفاقی طور پر آگیا لیکن اگر ہمیں ایک بوٹ دکھائی دیتا ہو جو اس چمڑے سے بنا ہوا ہو.پھر ہمیں وہی چمڑا کہیں صوفوں پر لگا ہوا نظر آئے.کہیں کرسیوں اور زینوں پر لگا ہوا دکھائی دے تو ان ساری چیزوں کو ہم اتفاق نہیں کہہ سکتے.پس نظامِ کلی اتفاقی نہیں ہوتا.جزئی چیز کو بے شک اتفاقی کہا جا سکتا ہے.پھر ہم دیکھتے ہیں خدا تعالیٰ نے ایک طرف آنکھ بنائی اور اُس آنکھ میں یہ مادہ رکھا کہ وہ بغیر روشنی کے نہیں دیکھ سکتی تو دوسری طرف کروڑوں کرروڑ میل پر سورج بنا دیا تا کہ آنکھ اس روشنی کے ذریعہ اردگرد کی چیزوں کو دیکھ سکے.اب بھلا اس کو کون اتفاق کہہ سکتا ہے؟ یہی حال اور ضروریاتِ انسانی کا ہے کوئی انسانی ضرورت ایسی نہیں جو طبعی ہو اور اُس کو پورا کرنے کے سامان اللہ تعالیٰ نے پیدا نہ فرمائے ہوں.بعض ضرورتیں ایسی ہیں جن کو پورا کرنے کے سامان اللہ تعالیٰ نے انسانی نفس میں ہی رکھ دئے ہیں.بعض ضرورتیں ایسی ہیں جن کو پورا کرنے کے سامان اللہ تعالیٰ نے انسان کے اردگرد رکھ دئے ہیںاور بعض ضرورتیں ایسی ہیں جن کو پورا کرنے کے سامان اللہ تعالیٰ نے کروڑوں کروڑ میل پر پیداکر دیئے ہیں.بہرحال ہر انسانی ضرورت کو پورا کرنے کے سامان اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں پیدا کئے ہوئے ہیں اور یہ نظام اپنی ذات میں ایسا مکمل ہے کہ اس ساری تصویر کو ملا کر کوئی شخص یہ خیال تک بھی نہیں کر سکتا کہ یہ سب کچھ اتفاقی ہو گیا ہے.پس فرماتا ہے تم اس نظام سماوی اور ارضی کو دیکھو جو خلق میں تمہاری اپنی پیدائش سے بھی زیادہ مشکل ہے.تم کسی ایک چیز کے متعلق کہہ سکتے ہو کہ وہ اتفاقی ہو گئی.تم دو کے متعلق کہہ سکتے ہو کہ وہ اتفاقی ہو گئیں لیکن تم اس سارے نظام کو کس طرح اتفاقی کہہ سکتے ہو کہ رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوّٰىهَا.وَ اَغْطَشَ لَيْلَهَا وَ اَخْرَجَ ضُحٰىهَا.وَ الْاَرْضَ بَعْدَ ذٰلِكَ دَحٰىهَا.اَخْرَجَ مِنْهَا مَآءَهَا وَ مَرْعٰىهَا.وَ الْجِبَالَ اَرْسٰىهَا.مَتَاعًا لَّكُمْ وَ لِاَنْعَامِكُمْ(النازعات:۲۹ تا ۳۴).نظام کی یہ ساری تصویر جو ہم تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں اس پر غور کرو اور بتائو کہ کیا یہ سب چیزیں اتفاقی ہو سکتی ہیں؟ میں سمجھتا ہوں دنیا کے عجیب سے عجیب فلسفہ پر بھی اگر کوئی شخص اپنے علم کی بنیاد رکھتا ہو تو وہ اسے اتفاقی نہیں کہہ سکتا.بلکہ اُسے تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ کارخانۂ عالم کے پیچھے
Page 192
ضرور کوئی اورہستی کام کر رہی ہے جو تمام ضروریات انسانی کو جانتی اور پھر ان کو پورا کرنے کے سامان بھی مہیا کرتی ہے.خدا تعالیٰ کے خالق ہونے پر نظام عالم کی شہادت پس فرماتا ہے تم اس نظام پر غور کرو.تم اپنے متعلق خیال کر سکتے ہو کہ ہم اپنے آپ خالق ہیں مگر تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نظام کا خالق اورکوئی نہیں.اس لئے ہم اپنی خالقیت منوانے کے لئے تمہارے سامنے اسی نظام کو پیش کرتے ہیں تم اس کو اچھی طرح دیکھو اور پھر سوچو کہ کیا تمہارا بھی کوئی خالق ہے یا نہیں.گویا ایک نہایت ہی لطیف پیرایہ میں انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کیا گیا.اگر انسان کو اپنی ذات کی طرف توجہ دلائی جاتی اور کہا جاتا کہ خدا نے تمہیں زبان دی ہے.کان دئے ہیں.آنکھیں دی ہیں.دل دیا ہے.دماغ دیا ہے.اور یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ تمہارا کوئی خالق ہے تو وہ انکار کر دیتا اور کہتا اِس کا فلاں سبب ہے اور اُس کا فلاں سبب ہے.بیشک ہم گفتگو کرتے ہوئے عام طور پر یہی مثال دیا کرتے ہیں مگر قرآن کریم چونکہ مکمل بات کرتا ہے.اِس لئے اُس نے کارخانۂ عالم کو اپنی خالقیت کے ثبوت میں پیش کیا ہے کیونکہ دوسری چیز کے متعلق سوچنا اور غور کرنا آسان ہوتا ہے جیسے کہتے ہیں ؎ خوشترآں باشد کہ سِرِّ دلبراں گفتہ آید در حدیثِ دیگراں (مثنوی مولوی معنوی مطبع منشی نول دفتر اول کشور صفحہ ۸) اپنے متعلق سوچنا اور غور کرنا اُتنا آسان نہیں ہوتا جتنا دوسری چیز کے متعلق غور کرنا آسان ہوتا ہے یہی حکمت ہے جس کی بناء پر قرآن کریم نے بجائے یہ طریق اختیار کرنے کے کہ تم غور کرو خدا نے تمہیں آنکھیں دی ہیں.دل دیا ہے.دماغ دیا ہے.کان دئے ہیں.ہاتھ اور پائوں دئے ہیں جو اس بات کا ثبوت ہیں کہ تمہارا کوئی خالق ہے یہ طریق اختیار کیا ہے کہ وہ انسان کے سامنے نظامِ عالم کی گواہی پیش کرتا ہے تا کہ اس کے متعلق سوچنا آسان ہو اور وہ لوگ جو ہستی باری تعالیٰ کے قائل نہیں ٹھنڈے دل سے اِس معاملہ پر غور کر سکیں.دوسری وجہ یہ ہے کہ انسان اشرف المخلوقات تو بے شک ہے مگر نکلااسی نظام سے ہے اور وُہ اس سارے نظام کا ایک ادنیٰ پُرزہ ہے.وہ اشرف ہو گیا ہے اپنی دماغی ترقی کیو جہ سے ورنہ جہاں تک اُس کی پیدائش کا سوال ہے وہ اپنی پیدائش کے لحاظ سے اس سارے نظام کا ایک جُزو اور پُرزہ ہے اور خلقت کے لحاظ سے زمین وآسمان کی پیدائش کے سامنے بالکل غیر اہم ہے پس جہاں تک خالی پیدائش کا سوال ہے.پیدائشِ عالم زیادہ اہم ہے اور پیدائش انسان اُس کے مقابلہ میں بہت حقیر چیز ہے.بعد میں کوئی چیز ارتقاء حاصل کر کے بڑی ہو جائے تو اِس سے
Page 193
نفسِ مسئلہ پر کوئی اثر نہیں پڑ سکتا.پس چونکہ پیدائشِ عالم پیدائشِ انسانی کی نسبت زیادہ اہم ہے اس لئے اللہ تعالیٰ پیدائشِ عالم کو پیش کر کے بتاتا ہے کہ جس نے اتنا بڑا کارخانہ بنا لیا وہ تم کو کیوں نہیں بنا سکتا.یہ دلیل پیش کرکے اللہ تعالیٰ نے ضمنی طور پر دو ۲ اور اہم مسائل کا بھی فیصلہ کر دیا ہے ایک ؔحیات بعد الممات کا اور دوسرے اسی عالم میں اُس احیاء روحانی کا جو انبیاء کے ذریعہ ہوتا ہے.پیدائش عالم کا مسئلہ حیات بعد الموت کے لئے ایک دلیل حیات بعدالممات کا تو اس رنگ میں ثبوت دیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا کارخانۂ عالم بنا دیا ہےجو تمہاری پیدائش سے بھی زیادہ اہم ہے اور جس نظام کا تم بھی ایک جزو ہو تو بہرحال تمہیںتسلیم کرنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ دوسرے عالم میں بھی پیدائش کر سکتا ہے.گویا یا تو یہ تسلیم کرو کہ یہ نظام خود بخود ہے اس کے پیچھے کوئی اور ہستی کام نہیںکر رہی اور اگر تم اس نظام کو دیکھ کر اور اس کی باریک در باریک حکمتوں پر غور کر کے یہ ماننے پر مجبور ہو کہ یہ نظام اتفاقی نہیں ہو سکتا بلکہ ایک اَور ہستی اس نظام کی خالق ہے تو تمہیں ماننا پڑے گا کہ جس خدا نے ایک دفعہ یہ سب کچھ بنا لیا وہ دوسری دفعہ بھی تم کو بنا سکتا ہے گویا ایک ہی دلیل سے اللہ تعالیٰ نے نہ صرف اپنی ہستی کا ثبوت پیش کر دیا بلکہ حیات بعدالموت کا مسئلہ بھی واضح کر دیا.آخر بعض لوگ مرنے کے بعد کسی اَور زندگی کے کیوں قائل نہیں؟ اِسی لئے کہ وہ خیال کرتے ہیں ایسا کب ہو سکتا ہے کہ مر کر انسان زندہ ہو جائے.اللہ تعالیٰ بتاتا ہے تم تو اس نظام کو ایک حقیر سا پُرزہ ہو.تم غور کرو کہ اتنا بڑا کارخانہ کس نے بنایا ہے.تمہیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ سب کارخانہ خدا نے بنایا ہے.جب خدا نے اس دنیا کو بنایا ہے تو جوخدا اتنا بڑا کارخانہ جاری کر سکتا ہے کیا وہ یہ طاقت نہیں رکھتا کہ دوبارہ تم کو پیدا کر دے.گویا جس طرح فَاَخَذَهُ اللّٰهُ نَكَالَ الْاٰخِرَةِ وَ الْاُوْلٰى میں عذابِ دنیا کو عذاب آخرت کا ثبوت قرار دیا گیا تھا اسی طرح اِس جہان کی پیدائش کو اگلے جہان کی پیدائش کا ثبوت قرار دیا گیا ہے.اور بتایا گیا ہے کہ جو خدا اس جہان میں تمہیں پیدا کر سکتا ہے وُہ تمہیں اگلے جہان میں بھی پیدا کر سکتا ہے.سوال صرف یہ رہ جاتا ہے کہ اُس نے دوبارہ پیدا کرنے کا وعدہ بھی کیا ہے یا نہیں؟ اگر وعدہ کیا ہے تو بات ختم ہو جاتی ہے اور یہ سوال نہیں رہتا کہ وُہ کس طرح کرے گا جب اُس نے اس جہان میں اتنا بڑا نظام پیدا کر کے دکھادیا ہے تو وہ اگلے جہان میں بھی پیدا کر سکتا ہے اُس کے لئے یہ ناممکن بات نہیں.گویا پیدائش عالم کا مسئلہ حیات بعدالموت کا بھی ایک رنگ میںثبوت ہے.اسی طرح یہاںروحانی احیاء کا مسئلہ بھی پیش کیا گیا ہے کہ جس خدا نے تمہاری ادنیٰ ادنیٰ ضرورتوں کو پورا کرنے کا اس قدر سامان کیا ہے کیا اُس خدا کے متعلق تم یہ خیال بھی کر سکتے ہو کہ اُس نے تمہارے روحانی اِحیاء کا کوئی
Page 194
سامان نہیں کیا ہو گا جب تمہارے جسم کی حفاظت کے لئے جو بہرحال ایک دن فنا ہو جانے والا ہے اللہ تعالیٰ نے اِس قدر سامان پیدا کر دئے ہیں جن میں سے بعض کروڑوں کروڑ میل پر ہیں تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری روح کی حفاظت کے لئے کیوں سامان نہیں کئے ہوں گے.وہ خدا جو عالم کبیر کا نظام ہر جہت سے مکمل رکھتا ہے عالم صغیر کی ضروریات پوری کرنے سے خواہ وہ روحانی ہوں یا جسمانی کس طرح اغماض کر سکتا تھا.رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوّٰىهَاۙ۰۰۲۹ (اور) اس کی بلندی کو اونچا کیا ہے پھر اُسے بے عیب بنایا ہے.حَلّ لُغَات.اَلسَّمْکُ اَلسَّمْکُ مصدر ہے سَمَکَ کا اور اس کے معنے بلند کرنے یا بلند ہونے کے ہوتے ہیں اور سَمْکٌ اسم بھی ہے اس صورت میں اس کے معنے چھت کے یا چھت سے تہ زمین تک کے فاصلے کے ہوتے ہیں اور اس کے معنے کسی چیز کی اونچائی کے بھی ہوتے ہیں (اقرب) کہتے ہیں سَنَامٌ سامکٌ.اونٹ کا اونچا کوہان (تاج ) اور موٹاپے کو بھی کہتے ہیں سَمْکَ الْمَنَارَۃِ یعنی مینارہ کی گولائی (اقرب) گویا اس کے معنوں میں دو چیزیں پائی جاتی ہیں یا تو فاصلہ ہو اور وہ چیز بہت اونچی ہو اور یا پھر خود وہ چیز قد میں اونچی ہو یا دَل میں موٹی ہو.ابن جزی کہتے ہیں اَلسَّمْکُ غِلْظُ السَّمَآ ئِ وَ ھُوَ الْاِرْتِفَاعُ الَّذِیْ بَیْنَ سَطْحِ السِّفْلِ الْاسْفَلِ الَّذِیْ یَلِیْنَا وَسَطْحُھَا الْاَعْلَی الَّذِیْ یَلِیْ مَا فَوْقَھَا یعنی سَمْک کے معنے آسمان کا دَلْ ہے اور اس سے مراد آسمان کی وہ بلندی ہے جو آسمان کی نچلی سطح اور اوپر کی سطح کے درمیان ہے (فتح البیان زیر آیت ھذا) اس کے معنوں میں ایک اختلاف بھی ہے اور وہ یہ کہ بعض لُغت والے کہتے ہیں سَمْکٌ کا لفظ خالی بلندی کی طر ف اشارہ نہیں کرتا بلکہ اعلیٰ سے اسفل کی طرف جانے کو سَمْکٌ کہتے ہیں.اقرب والے نے بھی یہی لکھا ہے کہ مِنْ اَعْلَی الْبَیْتِ اِلٰی اَسْفَلِہٖ لیکن بعض دوسرے ادیب اس کے خلاف نیچے سے اوپرکے معنے کرتے ہیں صاحب کشاف زیرآیت ھذا لکھتے ہیں رَفَعَ سَمْکَھَا اَیْ جَعَلَ مِقْدَارَ ذِھَابِھَا فِیْ سِمْتِ الْعُلُوِّ مدِیْدًا رَفِیْعًا یعنی نیچے سے اوپر تک اس کا دَلْ لمبا اور اونچا ہے.پس سَمْکٌ نام ہے نیچے سے اوپر کی طرف جانے کا گویا مِنْ اَعلَی الْبَیْتِ اِلٰی اَسْفَلِہٖ کی بجائے مِنْ اَسْفَلِ الْبَیْتِ اِلٰی اَعْلَاہُ کو سَمْکٌ کہتے ہیں.بعض ادیب اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ اعلیٰ سے اسفل کی طرف نسبت بتانے کے لئے عربی زبان میں عُمْق کا لفظ پایا جاتا ہے(مفردات ) چنانچہ جب عُمْق کا لفظ کہا جاتا ہے تو اس سے مراد اوپر سے نیچے کی
Page 195
نسبت ہی ہوتی ہے لیکن جب ہم سَمْکٌ کہتے ہیں تو اس سے مراد نیچے سے اوپر کی طرف جانا ہوتا ہے مگرقرآن کریم سَمْکٌ کا لفظ بیان کرنے کے بعد نیچے سے اوپر کی طرف جانے کی بجائے اُوپر سے نیچے کی طرف آیا ہے چنانچہ آسمان کا ذکر کرنے کے بعد فرماتا ہے اَغْطَشَ لَيْلَهَا وَ اَخْرَجَ ضُحٰىهَا.وَ الْاَرْضَ بَعْدَ ذٰلِكَ دَحٰىهَا.اَخْرَجَ مِنْهَا مَآءَهَا وَ مَرْعٰىهَا.وَ الْجِبَالَ اَرْسٰىهَا.مَتَاعًا لَّكُمْ وَ لِاَنْعَامِكُمْ.یہاں بلندی کی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے پہلے بیان کیا ہے اور زمین کی چیزوں کو بعد میں بیان کیا ہے.پس قرآنی ترتیب کے مطابق ان لوگوں کے معنے زیادہ صحیح معلوم ہوتے ہیں جو کہ سَمْک اوپر سے نیچے کی طرف نسبت رکھنے کو کہتے ہیں.یہ بھی ممکن ہے کہ درحقیقت یہ لفظ دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہو.فَسَوّٰھَا.پھر ہم نے اُس کو بے عیب بنایا.کہتے ہیں سَوَّی الشَّیْ ءَ: جَعَلَہٗ سَوِیًّا اَیْ لَا دَاءَ بِہٖ وَلَا عَیْب (اقرب) کسی چیز کو ایسا بنایا کہ اس میں کوئی عیب نہ رہے.تفسیر.فرماتا ہے اگر تم نظامِ عالم پر نظر دوڑائو تو تمہیں معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ ساری چیزیں نامکمل رہتیں اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلندیاں نہ بنائی جاتیں.اِن بلندیوں نے زمین کے نقائص اور اُس کے عیوب کو ڈھانک دیا ہے اور تمام چیزیں ایک مکمل صورت میں دکھائی دیتی ہیں.اگر اللہ تعالیٰ سورج اور چاند اور ستارے اور دوسرے بڑے بڑے سیّارے نہ بناتا تو زمین کا قیام بالکل ناممکن ہوتا.درحقیقت سورج چاند اور ستاروں کی کشش کی وجہ سے ہی زمین رہنے کے قابل ہوئی ہے اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلندی پر ان اجرامِ فلکی کو پیدا نہ کیا جاتا تو وہی زمین جو آج تمہیں بے عیب دکھائی دیتی ہے وہی زمین جو تمہارے کھانے کا سامان پیدا کرتی ہے.وہی زمین جو تمہارے لئےپینے کا سامان مہیا کرتی ہے.اُسی زمین میں تمہیں سَو سَو خرابیاں نظر آتیں بلکہ درحقیقت یہ زمین بنی نوع انسان کے رہنے کے قابل نہ ہوتی.آسمان ہی ہے جس نے زمین کے عیوب کو ڈھانکا.اور وہی بلندیاں ہیں جن سے دن پیدا ہوا جس میں تم کسبِ معاش کے ذرائع اختیار کرتے ہو.اور انہی بلندیوں کے نتیجہ میں رات پیدا ہوئی جس میں تم آرام کرتے ہو اور اپنی کھوئی ہوئی طاقتوں کو دوبارہ حاصل کرتے ہو.پس اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اُس نے آسمان بنایا اور اُس آسمان کو بلندی کی نسبت وسیع کیا.فَسَوّٰىهَا میں فاء نتیجہ اور ترتیب کے لئے ہے مراد یہ ہے کہ اُس نے بلندی کو بہت اونچا کیا اور پھر اُسے اونچا کر کے اُس کے نتیجہ میں زمین کوبے عیب بنایا.گویا فَسَوّٰىهَاکی فاء اس مضمون کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ دنیا کا نظام کبھی مکمل نہ ہوتا اگر اس کے اوپر ایک اور نظام قائم نہ ہوتا.
Page 196
انسان کا بے عیب ہونا اس کی بلندی اور وصول الی اللہ سے تعلق رکھتا ہے اس آیت میں اس امر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ انسان کا بے عیب ہونا بھی اُس کی بلندی اور وصول الی اللہ سے تعلق رکھتا ہے.دنیا میں خواہ بڑے بڑے صنّاع ہوں.بڑے بڑے انجینئر ہوں.بڑے بڑے مہندس ہوں یہ دنیا یوں معلوم ہوتی ہے جیسے وحشیوں سے بھری ہوئی ہے نہ انہیں اخلاق کا خیال ہوتا ہے نہ انہیں روحانیت کی طرف توجہ ہوتی ہے نہ انہیں خدا تعالیٰ کی محبت کا احساس ہوتا ہے وہ مادی دنیا اور اس کے لذائذکی طرف اسی طرح جھکے ہوئے ہوتے ہیں جس طرح جانور کھانے پینے کی طرف متوجہ رہتا ہے لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء آتے ہیںتو پھر وہی دنیا جو وحشت و بربریت کا منظر پیش کر رہی ہوتی ہے حسین صورت میںنظر آنے لگتی ہے.دلوں میں اخلاص پیدا ہو جاتا ہے.آنکھوں میں محبت کی چمک ظاہر ہونے لگتی ہے.وہ دل جو کبھی خدا تعالیٰ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے اب اُن میں بھی محبت کی ٹیسیں اُٹھنی شروع ہو جاتی ہیں اور دنیا رہنے کے قابل نظر آنے لگتی ہے.اُس وقت وہی فلسفی جو خدا سے دُور ہوتا ہے انبیاء کے نور کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف کھنچا چلا جاتا ہے بڑے بڑے انجینئر اور صناع اور موجد جن کی طاقتیں ضائع ہو رہی ہوتی ہیں پھر صحیح راستوں پر چلنے لگ جاتے ہیں اور اُن کے سارے عیب اور اُن کی ساری کمزوریاں جاتی رہتی ہیں پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم دنیا کو بے عیب دیکھنا چاہتے ہو تو آسمان کی ضرورت سے کبھی انکار مت کرو.جس طرح عالمِ کبیر میں کوئی زمین آسمان کے بغیر نہیں رہ سکتی اسی طرح عالمِ صغیر کا حُسن اس وقت تک ظاہر نہیں ہوسکتا جب تک آسمان سے وحی نازل نہ ہو اللہ تعالیٰ کا کلام نازل نہ ہو اور انبیاء اس کے حسن کو نمایاں کرنے والے مبعوث نہ ہوں اگر تم یہ تسلیم کرتے ہو کہ خدا تعالیٰ نے زمین کے قیام کے لئے آسمان بنا یا اور آسمان کے قیام کے نتیجہ میں ہی زمین بے عیب بنی تو پھر تمہیںیہ بھی تسلیم کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام اور اس کا الہام بھی ضروری ہے.اگر خدا تعالیٰ کی طرف سے کلام نہ اُترے اگر اس کی طرف سے انبیاء مبعوث نہ ہوں تو پھر دنیا میں عیب ہی عیب نظر آئیں.کمزوریاں ہی کمزوریاں دکھائی دیں.گناہ ہی گناہ چھائیں رہیں.خدا تعالیٰ کا تازہ کلام اور اُس کے انبیاء کی بعثت ہی ہے جو دنیا کے عیوب کو ڈھانکتی ہے اور جس کے بعد وہ ایک حسین صورت میں دکھائی دینے لگتی ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تفصیل بتائی ہے کہ اُس نے کس طرح تسویہ کیا اور اس کے کیا کیا نتائج ظاہرہوئے.
Page 197
وَ اَغْطَشَ لَيْلَهَا وَ اَخْرَجَ ضُحٰىهَا۪۰۰۳۰ اور اس کی رات کو (تو) تاریک بنایا ہے اور اس کی دوپہر کو (روشن کر کے) نکالا ہے.تفسیر.اَغْطَشَ لَيْلَهَامیں لَيْلَهَا کی ضمیر کا مرجع اَغْطَشَ لَیْلَھَا خدا نے اس کی رات کو تاریک بنایا وَ اَخْرَجَ ضُحٰىهَا اور اس کے دن کو نکالا یا اُس کی دھوپ یا دوپہر کو ظاہر کیا.یہ مراد نہیں کہ ایک چیز کو اُس نے دوسری شکل دے دی بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس کی رات اندھیری ہے اور اُس کا دن روشن ہے.اَغْطَشَ لَیْلَھَا میں ھَاء کی ضمیر آسمان کی طرف پھیری گئی ہے اور ضُحٰی میں بھی ضمیر اسی کی طرف لوٹائی گئی ہے.حالانکہ زمین پررات سورج کے سامنے نہ ہونے کی وجہ سے آتی ہے آسمان پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا اس لئے وہ رات ہماری رات ہوتی ہے آسمان کی رات نہیں ہوتی.اسی طرح ضُحٰی بھی ہماری ہوتی ہے آسمان کی نہیں ہوتی.پس یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ دونوں ضمیریں آسمان کی طرف کیوں پھیری گئی ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سورج اور چاند چونکہ آسمان کا حصہ ہیں اور رات ہمیشہ سورج کے غروب ہونے سے آتی ہے جو بلندی پر واقعہ ہے اس لئے لَیْل کو سماء کی طرف منسوب کر دیا گیا.اس کا یہ مطلب نہیں کہ رات آسمان پرآتی ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ وہ رات جو اس نظام کے نتیجہ میں پیدا ہوتی ہے اس نظام کا کام دنیا کو روشنی پہنچانا ہے مگر جب دنیا سورج کے سامنے نہیں ہوتی تو روشنی نہیں آسکتی اور اندھیرا چھا جاتا ہے پس رات کو آسمان کی طرف اس لئے منسوب کیا گیا ہے کہ یہ رات نظامِ سماوی سے تعلق رکھتی ہے اور اس کا ایک حصہ ہے.اسی طرح ہم ضُحٰی کوضُحَی السَّمَآء بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ ہماری ضُحٰی بھی نظامِ سماوی سے تعلق رکھتی ہے.دُوسرا جواب یہ ہے کہ سماء سے مراد کوئی مادی شئے نہیں بلکہ بالائی جوف ہے اس لئے رات اور دن اس کی طرف منسوب ہو سکتے ہیں.فرماتا ہے رات اور دن میں سے ایک کو ہم نے تاریک بنایا ہے اور دوسرے کو روشن بنایا ہے.اس آیت میں اس امر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ رات گمنامی کا زمانہ ہوتا ہے جس میں انسانی طاقتیں پوشیدہ رہتی ہیں اور اُن طاقتوں کا ظہور اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک دن کی روشنی رات کی ظلمت کو دُور نہیں کر دیتی.اسی طرح جبتک نبی کا ظہور نہ ہو لوگوں کی قابلیتیں مخفی رہتی ہیں ان کی استعدادوں کا ظہور نہیں ہوتا وہ خواہ طبعی طور پر اپنے اندر بعض اوصاف رکھتے ہوں اُن سے دنیا ناواقف رہتی ہے جب تک نبوت کا سورج ان کی حقیقت کو ظاہر نہیں کر دیتا اور ان کی چھپی ہوئی استعدادوں کو اُبھار نہیں دیتا.یہ ایک قانون ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عالمِ روحانی اور عالمِ جسمانی
Page 198
دونوں میں کام کرتا دکھائی دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسی قانون کا اس جگہ ذکر کرتے ہوئے اہل عرب کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے تم اپنے متعلق یہ خیال کرتے ہو کہ تمہارے اندر بہت بڑی قابلیتیں پائی جاتی ہیں.تم بہادری میں یکتا ہو.تم سخاوت میں نامور ہو.تم پابندیٔ عہد میں ایک نمایاں خصوصیت اپنے اندر رکھتے ہو لیکن تمہیںعلم ہونا چاہیے کہ جب تک نبی نہیں آتا اُس وقت تک ان طاقتوں کا مکمل ظہور نہیں ہو سکتا.نبی کے آنے سے پہلے بے شک قوم میں یہ استعدادیں موجود ہوتی ہیں مگر لوگوں کا دائرۂ عمل نہایت محدود ہوتاہے.اور بوجہ اس کے کہ کوئی نظام اُن میں نہیں ہوتا ان خوبیوں سے اجتماعی طور پر قوم کو فائدہ نہیں پہنچ سکتا.لیکن جب نبی آجاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اُس کے ذریعہ ایک نیا نظام قائم فرماتا ہے تو اس وقت افرادِ قوم کی استعدادیں اُبھرنی شروع ہو جاتی ہیں اور ہر شخص کا وصف نمایاں ہو کر قوم کے سامنے آنا شروع ہو جاتا ہے.سخاوت وہ پہلے بھی کر رہے ہوتے ہیں.بہادری وہ پہلے بھی دکھا رہے ہوتے ہیں.مہمان نوازی کا وصف اُن میں پہلے بھی موجود ہوتا ہے.پابندیٔ عہد کی عادت اُن میں پہلے بھی پائی جاتی ہے مگر ان کا دائرہ ایسا محدود ہوتا ہے کہ دنیا کی نگاہ ان خوبیوں کی طرف نہیں اٹھتی.مگر جب انبیاء کے ذریعہ اللہ تعالیٰ ایک نیا نظام قائم کر دیتا ہے اور تمام لوگوں کو ایک سلک میں منسلک کر دیتا ہے تو پھر ہر ایک کی قابلیت نمایاں طور پر دنیا کے سامنے آجاتی ہے اور اُسےاِس امر کا قائل ہونا پڑتا ہے کہ یہ لوگ اپنے اندر ترقی کی حیرت انگیز قابلیت رکھتے ہیں.اُس وقت ان کی سخاوت بھی ایک تنظیم میں آجاتی ہے.اُن کی جرأت اور بہادری کی رُوح بھی منظم رنگ میں ظاہر ہوتی ہے اور اُن کی ذاتی اور اخلاقی خوبیاں بھی قوم کے لئے ایک نمونہ قرار پا جاتی ہیں.اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ خوبیاں لوگوں میں پہلے بھی موجود ہوتی ہیں مگر اُس وقت رات کی ظلمت نے ان خوبیوں پر پردہ ڈالا ہوا ہوتا ہے جب دن چڑھتا ہے.جب نبوت کا سورج اُن پر طلوع کرتا ہے تو ہر شخص کی آنکھ ان کی طرف اٹھنی شروع ہو جاتی ہے.اُن کی وہی خوبیاں جو پہلے کسی کو نظر نہیں آتی تھیں اب ہر ایک کو دکھائی دینے لگتی ہیں اور تحسین و آفرین کی آوازیں ان کے متعلق سنائی دینے لگتی ہیں.چنانچہ دیکھ لو.تاریخی شہادت اس امر پر موجود ہے کہ عربوں میں بہادری کی روح پہلے بھی پائی جاتی تھی.کفر کی حالت میں بھی وہ نڈر تھے.وہ دلیر اور بہادر تھے.مگر ان کا یہ وصف دنیا کی نگاہوں سے بالکل اوجھل تھا.عرب کے لوگ بے شک اپنے اس ذاتی جوہر سے آگاہ ہوں مگر دنیا کا اَور کون سا ملک تھا جو عربوں کی اس بہادری سے واقف تھا؟ پس بے شک عربوں میں بہادری تھی مگر رات کی ظلمت نے اُن کی اس خوبی کو ڈھانکا ہوا تھا جب رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم کے نور کی روشنی اُن پر پڑی تو جیسے پالش رنگ کو چمکا دیتی ہے اسی طرح ان کا رنگ چمک گیا.اُن کی بہادری کی روح اُبھری اور ایسے جوش اور ایسی شان سے اُبھری کہ
Page 199
آج دنیا کی تاریخیں عربوں کی بہادری کے واقعات سے بھری پڑی ہیں.اسی طرح سخاوت کو لو.اس امر سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا کہ عربوں میں آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم کی بعث سے پہلے بھی سخاوت کی روح موجود تھی مگر اسلام کے ظہور نے اہلِ عرب کو یہ سبق دیا کہ و ہ اِحْتِسَابًا اس خُلق سے کام لیں اور اللہ تعالیٰ کی رضاء اور اُس کی محبت کے حصول کے لئے سخاوت کیا کریں.پھر دوسرا فائدہ اہلِ عرب کو یہ ہوا.کہ گو پہلے بھی سخاوت کی روح اُن میں موجود تھی مگر دنیا اُن اس خوبی سے ناواقف تھی اسلام کی روشنی جب اُن کے چہرہ پر پڑی.جب اُس آفتاب نے رات کی ظلمت کا پردہ چاک کر دیا تو دنیا پر اہل عرب کی سخاوت کا ایسا شہرہ ہوا کہ آج تک اُن کی سخاوت کی داستانیں اَوراقِ تاریخ پر نظر آتی ہیں.آنحضرت صلعم کی بعثت کا اثر اہل عرب کی عادات پر اسی طرح انسانی اخلاق میں سے ایک نمایاں خلق پابندیٔ عہد ہے جس پر اسلام نے خاص طور پر زور دیا ہے مگر اس سے کون انکار کر سکتا ہے کہ عربوں میں اسلام سے پہلے بھی یہ خوبی موجود تھی.فرق تھا تو یہ کہ اُن کی اس خوبی کو جِلا حاصل نہیں تھی.اسلام کا ظہور اُن کی اس خوبی کو نمایاں کرنے کا موجب بن گیا.اسلام سے قبل ہر شخص اس وصف کو صرف اپنی ذات تک محدود رکھتا تھا قومی معاملات میں اس کی پروا نہیں کی جاتی تھی مگر اسلام نے ذاتی اور قومی ہر دو امور میں پابندیٔ عہد کو ایک ضروری امر قرار دیا.اور اس کی خلاف ورزی کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا موجب بتایا.اسی طرح جب اسلام کا سورج چڑھا تو اہلِ عرب کو مزید فائدہ یہ ہؤا کہ اُن کے اس حُسن کی طرف دنیا کی توجہ کھچ گئی.جس طرح رات کو کچھ پتہ نہیں لگتا کہ خوبصورت چیز کون سی ہے اور بد صورت کونسی.لیکن جب دن چڑھتا ہے تو حُسن والے کا حُسن نمایاں ہو جاتا ہے اور نقص والے کا نقص نمایاں ہوجاتا ہے.اسی طرح بے شک اہل عرب میں یہ خوبی موجود تھی مگر اسلام نے اُن کی اس خوبی کو ایسی جِلا بخشی کہ تاریخیں اہل عرب کی پابندیٔ عہد کے واقعات سے بھری پڑی ہیں.ہم بچے تھے کہ ہمیں انگریزی ریڈروں میں یہ واقعہ پڑھایا جاتا کہ سپین میں ایک یوسف نامی تاجر گزرا ہے ایک دفعہ اُس کے لڑکے کو کسی شخص نے قتل کر دیا اور پھر وہ قاتل بھاگ کر اُسی مقتول کے باپ کے پاس گیا اور کہنے لگا مجھے پناہ دو اُسے علم نہیں تھا کہ میں اُسی کے لڑکے کو قتل کر کے آرہا ہوں اور یوسف کو یہ معلوم نہیں تھا کہ میرا لڑکا اسی کے ہاتھوں قتل ہو چکا ہے مگر جب اُس نے کہا کہ مجھے پناہ دی جائے سپاہی میرے تعاقب میں آرہےہیں تو یوسف نے کہا بہت اچھا اور یہ کہہ کر اُس نے اُسے اپنے ایک کمرہ میں چھپا دیا.تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ سپاہی اُس کے بیٹے کی لاش اٹھائے وہاں آنکلے اور انہوں نے کہا کہ ابھی ابھی ایک شخص نے تمہارے اس بیٹے کو قتل کر دیا ہے اور ہم نے
Page 200
دیکھا ہے کہ قاتل بھاگ کر اسی طرف آیا ہے کیا تمہیں اس کا کچھ پتہ ہے؟ یوسف تاجر نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اُس کا بیٹا قتل ہو چکا ہے اور اُس وقت اُسے معلوم ہو گیا کہ وہ شخص جو میرے پاس پناہ کے لئے آیا ہے وہی میرے بیٹے کا قاتل ہے مگر عہد کی خلاف ورزی کو اُس نے برداشت نہ کیا اور اُس نے سپاہیوں کو کچھ ایسا جواب دیا کہ وہ مایوس ہو کر وہاں سے چلے گئے اور انہوں سمجھا کہ قاتل کسی اور طرف بھاگ گیا ہے.جب سپاہی چلے گئے تو اُس نے اپنے پچھواڑے کا دروازہ کھولا اور قاتل سے کہا کہ سپاہی چلے گئے ہیں تم اب بھاگ جائو.یہ پابندیٔ عہد کا ایسا شاندار نمونہ ہے کہ یوروپین لوگوں کو سارے یورپ میں اس قسم کی کوئی مثال نظر نہیںآئی اور اسلام سے شدیددشمنی رکھنے کے باوجود وہ اس بات پر مجبور ہوئے ہیں کہ اس واقعہ کو پیش کریں چنانچہ وفائے عہد کی مثال میں یہ قصہ اب تک اُن کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے حالانکہ یہ ایک مسلمان کا واقعہ ہے.پس گو یہ چیز پہلے بھی عربوں میں پائی جاتی تھی اور اس سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا.مگر اسلام کے آنے پر وہ حُسن بہت نمایاں ہو گیا اور دوسرے اس سے پہلے وہ خوبی اس طرح ظاہر نہ ہوتی تھی کہ دنیا کی توجہ کو اپنی طرف کھینچ سکے مگر جب رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم کی روشنی اُن پر پڑی تو اُن کا حُسن دنیا کے سامنے آگیا اور جس طرح سورج کی روشنی کے بعد کوئی چیز مخفی نہیں رہ سکتی اسی طرح اُن کی مخفی قابلیتیں اُبھرنی شروع ہو گئیں اور لوگوں کی نظریں اُن پر جم گئیں.پس اللہ تعالیٰ اہل عرب کو توجہ دلاتا ہے اور فرماتا ہے ہم نے مان لیا تمہارے اندر فطری طور پر بعض قابلیتیں پائی جاتی ہیں مگر تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان قابلیتوں کے ظہور کے لئے دن کی روشنی بھی ضروری ہے اگر تم اس روشنی میں نہیں چلو گے تو تمہاری قابلیتیں دنیا کی نگاہ سے بالکل مخفی رہیں گی لیکن اگر آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم کا نور تم پر پڑنے لگا تو یہ روشنی تمہاری استعدادوں کو ایسی جِلا بخشے گی کہ ہر شخص کی نگاہ تمہاری طرف اُٹھنے لگے گی اور باہر کی اقوام بھی تمہارے حسن کو دیکھنے لگیں گی.وَ الْاَرْضَ بَعْدَ ذٰلِكَ دَحٰىهَاؕ۰۰۳۱اَخْرَجَ مِنْهَا مَآءَهَا وَ اور اس کے ساتھ (یعنی اسی زمانہ میں) زمین کو بھی بچھایا ہے پھر (اس میں سے) اس کا پانی اور اس کا چارہ نکالا ہے.مَرْعٰىهَا۪۰۰۳۲وَ الْجِبَالَ اَرْسٰىهَاۙ۰۰۳۳ اور پہاڑوں کو بھی اس نے اس میں گاڑا ہے.حلّ لغات.بَعْدَ.یہ قَبْل کے مقابل معنے ادا کرنے کے لئے لایا جاتا ہے اور کبھی اس کے معنے مَعَ
Page 201
(یعنی ساتھ) کے بھی ہوتے ہیں (اقرب) پس وَالْاَرْضَ بَعْدَ ذَالِکَ دَحٰھَا کے دونوں معنے ہو سکیں گے (۱) زمین کو اس کے بعد بچھایا (۲) زمین کو اس کے بننے کے ساتھ ساتھ ہی بچھایا.دَحٰی دَحٰی کے معنے ہوتے ہیں بَسَطَ یعنی اُس نے پھیلایا (اقرب) دَحَی الْاَرْضَ.اَوْسَعَھَا.زمین کو وسیع بنا یا.(لسان) تفسیر.یہاں بَعْدَ ذَالِکَ کے دونوں معنے ہو سکتے ہیں بعدؔ کے بھی اور ساتھؔ کے بھی.یعنی یہ معنے بھی ہو سکتے ہیں کہ نظامِ شمسی کے بعد زمین کو پھیلایا گیا اور یہ معنے بھی ہو سکتے ہیں کہ نظام شمسی کے ساتھ ہی زمین کوپھیلانے کا کام کیا گیا.زیادہ صحیح معنے یہاں ساتھؔ کے ہی ہیں کہ ہم نے زمین کو اس نظام شمسی کے بنانے کےساتھ ہی بچھایا.زمین کے پھیلائے جانے کے دو معنے یہاں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ نظام شمسی کے پیدا ہونے پر زمین کو پھیلایا گیا ہے.پھیلانے سے یہ مراد نہیں کہ اسے بستر کے طور پر پھیلایا گیا بلکہ یہ مراد ہے کہ اس کے بعد زمین رہنے کے قابل ہوئی.جہاں تک جیالوجی کا تعلق ہے گو ہم اُس کے پابند نہیں مگر اُس کی تحقیق قرآن کریم کی اِس آیت کی پوری طرح تصدیق کرتی ہے.علم طبقات الارض کے ماہرین اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ پہلے زمین میں شدید گرمی تھی گرمی کے ابخرات سے پانی بنا اور پھر لاوا نکل نکل کر پہاڑوں کی صورت میں تبدیل ہوتا چلا گیا.یہ لازمی بات ہے کہ جب زمین میں سے کچھ مادہ نکل کر ایک بلند پہاڑ کی شکل اختیار کر لے گا تو دوسری طرف سے زمین نیچے دھنس جائے گی چنانچہ زلزلوںسے ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایک طرف سے زمین اُوپر کو نکل کر آتی ہے اور دوسری طرف سے زمین نیچے چلی جاتی ہے.جب زمین کا گرم مادہ نکل کر ایک طرف اونچا ہو گیا تو اس کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ دوسری طرف گڑھا پڑ جاتا.چنانچہ جوں جوں پہاڑ بنتے چلے گئے زمین کا ایک حصہ نیچے کی طرف دبتا چلا گیا اور چونکہ پانی ہمیشہ ڈھلوان کی طرف جاتا ہے اس لئے جب زمین کا ایک حصّہ نیچا ہو گیا تو پانی وہاں جمع ہو کر سمندر بن گیا.سمندر درحقیقت قائم مقام ہیں اُس مادہ کے جو زمین میںسے نکلا اور پہاڑوںکی شکل اختیار کر گیا.جب ایک طرف پہاڑ بلند ہو گئے اور دوسری طرف پانی سمٹ کر نیچے کی طرف چلا گیا تو زمین کی سطح ہموار ہو گئی اور وہ انسانی آبادی کے قابل بن گئی.مگر بہرحال یہ ایک قیاسی بات ہے ممکن ہے بعد میں کوئی اور تحقیقات اس کوغلط ثابت کر دے.اسی طرح زمین کی پیدائش کے متعلق سائنس والوں کا نظریہ یہ ہے کہ زمین اور دوسرے اجرام نظام شمسی ایک کُرّہ کے جو ابھی ٹھوس نہ ہوا تھا حصّہ تھے جو اُس کی تیز گردش کی وجہ سے اُس سے کٹ کر الگ ہو گئے.وہ کہتے ہیں جس طرح بچے بعض دفعہ آٹا لے کر زور سے گھماتے ہیں اور اس کے ٹکڑے ادھر ادھر جا پڑتے ہیں.اسی طرح اس نیم سیّال کرّہ
Page 202
نے جب تیز گردش کی تو اُس کے ٹکڑے اڑ کر اِدھر اُدھر جا پڑے اور وہ سرد ہو کر مختلف کرّوں کی شکل اختیار کر گئے.بہرحال نظام شمسی کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کئے جن سے یہ زمین رہائش کے قابل ہوئی.اگر نظام شمسی نہ ہوتا تو زمین کا قیام بھی نہ ہوتا.اِسی طرح نظامِ جسمانی بھی نظام شمسی روحانی کےقیام بعد قابلِ قدر ہوتا ہے.جس طرح نظامِ ارضی میں نظامِ شمسی کا وجود نہایت ضروری ہے اگر وہ نظام نہ ہوتا تو نہ پہاڑ بنتے نہ گڑھے پیدا ہوتے نہ سمندر تیار ہوتے.نہ انسان اس میں رہائش اختیار کر سکتے.اسی طرح جب تک نظامِ شمسی روحانی کےقائم نہ ہو جو انسان کے اندرونی آتش فشاں مادوں کو نکال کر باہر پھینک دے اور اس کی طبیعت میں یکسانیت پیدا کر دے اس وقت تک نظامِ جسمانی بھی اپنے اندر کوئی حقیقت نہیں رکھتا.نظامِ شمسی روحانی ہی ہے جو ایک طرف غصّہ کو دباتا ہے دوسری طرف انتہائی نرمی اور بے حیائی سے بچاتا ہے اور اس طرح اعتدال کی تعلیم دے کر اُسے بنی نوع انسان کے لئے مفید اور کارآمد وجود بناتا ہے گویا جس طرح زمین کے لاوا کو اللہ تعالیٰ پہاڑوں کی صورت میں زمین سے باہر نکال دیتا ہے اسی طرح مذہب ایک طرف انسان کے غضب اور جوش اور انتقام کی روح کو بعض پابندیوں کے نیچے لا کر ٹھنڈا کرتا ہے اور دوسری طرف وہ یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ آگ بالکل ختم ہو جائے اور گرمی کا مادہ بالکل نہ رہے.چنانچہ وہ ایسی تعلیم بھی دیتا ہے جو بے حیائیوں سے بچانے والی بے غیرتیوں سے محفوظ رکھنے والی اور سستی اور کاہلی سے نفرت دلانے والی ہوتی ہے جب ہر قسم کے خراب مادے دور ہو جاتے ہیں اور جب ہر قسم کے نیک مادے فطرتِ انسانی میں پیدا ہو جاتے ہیں تب یہ نظامِ جسمانی قابلِ قدر ہوتا ہے اگر اس نظام پر ایک روحانی آسمان نہ ہو اور اگر یہ نظام روحانی ایک طرف انسان کے حیوانی جذبات کو نہ دبائے اور دوسری طرف سستی اور غفلت کے جذبات کو دُور نہ کرے تو یہ نظام اپنے اندر کسی قسم کی جاذبیت اور کشش نہیں رکھ سکتا.یہ آسمانی نظام ہی ہے جس کے بعد روحانی غذا اور شرب کے سامان پیدا ہوتے ہیں اور پہاڑوں کی طرح زمین کو قائم رکھنے والے وجود پیدا ہو تے ہیں.مَتَاعًا لَّكُمْ وَ لِاَنْعَامِكُمْؕ۰۰۳۴ (یہ سب کچھ) تمہارے اور تمہارے جانوروں کے فائدہ کے لئے (اس نے کیا ہے).حَلّ لُغَات.اَنْعَامُ: اَنْعَامٌ نَعَمٌ کی جمع ہے اور اَلنَّعَمُ کے معنے ہیں اَلْاِبِلُ وَالشَّاءُ وَقِیْلَ خَاصٌ بِالْاِبِلِ یعنی نَعَم کا لفظ اونٹ اور بکریوں پر بولا جاتا ہے اور بعض کہتے ہیں کہ یہ لفظ صرف اونٹوں پر بولا
Page 203
جاتا ہے.اور کتاب مصباح میں لکھا ہے اَلنَّعَمُ: اَلْمَالُ الرَّاعِیْ وَھُوْ جَمْعٌ لَا وَاحِدَلَہٗ مِنْ لَفْظِہٖ وَاَکْثَرُ مَا یَقَعُ عَلَی الْاِبِلِ کہ نَعَم تمام چرنے والے جانوروں کو کہتے ہیں ہاں کثرت سے اس لفظ کا استعمال اونٹوں کے لئے ہی کرتے ہیں اور لفظ نَعَم جمع ہے اس کے مادہ (ن ع م) سے اس کا کوئی مفرد نہیں (جیسے عربی میں نِسْوَۃٌ کا لفظ ہے جس کے معنے عورتوں کے ہیں اس کا مفرد اس کے مادہ سے نہیں آتا بلکہ مفرد کے لئے اِمْرَأَۃٌ کا لفظ استعمال ہوتا ہے) بعض آئمۂ لغت کا قول ہے کہ نَعَمْ کا لفظ اونٹوں کے لئے خاص ہے لیکن اَنْعَام میں اونٹ.بھیڑ.گائے سبھی شامل ہیں پھر لکھتے ہیں کہ اَنْعَام کا لفظ بھیڑ.اونٹ اور گائے کے مجموعہ پر بولا جاتا ہے لیکن اگر اونٹوں کو اُن سے علیحدہ کیا جائے تو اونٹوں کے لئے نَعَم کا لفظ بولا جائے گا مگر صرف گائے.بھیڑ ،بکریوں کو نَعَم نہیں کہیں گے (اقرب) تفسیر.جسمانی اور روحانی ہر دو نظاموں میں چوپاؤں کی ضرورت کا احساس.نظامِ عالم کو پیش کر کے اس جگہ جسمانی طور پر یہ نتیجہ نکالا گیا ہے کہ یہ نظام نہ صرف تمہارے فائدہ کے لئے ہے بلکہ تمہارے چوپائوں کا بھی اس نظام میں خیال رکھا گیا ہے اور اُن کی رہائش اور حیات کے لئے جن چیزوں کی ضرورت تھی اُن کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہیا کیا گیا ہے.اس جسمانی نظام کو پیش کرتے ہوئے اس امر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ہمارا یہ طریق صرف اس ظاہری نظام میں ہی نہیں بلکہ روحانی عالم میں بھی جانوروں کا خیال رکھا جاتا ہے چنانچہ قرآن کریم میں اس مضمون پر خاص طور پر زور دیا گیا ہے اور مومنوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ ہر ایک کو اُس کا حق ادا کریں.چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَفِیْ اَمْوَالِھِمْ حَقٌ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ (الذاریات :۲۰) کہ مومن کے اموال میں سائل اور محروم دونوں کا حق ہے ان کا بھی جو مانگ سکتے ہیں اور ان کا بھی جو مانگ نہیں سکتے.جیسے کم گو اور گری ہوئی اقوام یا جانور وغیر ہ ہیں اور رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بھی اس امر کا خیال رکھنے کی تاکید فرمائی ہے چنانچہ آپ فرماتے ہیں ایک عورت کو محض اس لئے جنت میں داخل کیا گیا کہ اُس نے پیاسے کُتے کو پانی پلایا تھا (مسلم کتاب السلام باب فضل ساقی البھائم المحترمة واطعامھا) اسی طرح آپ نے فرمایا ہے جانوروں پر رحم کیا کرو کیونکہ خدا نے ان کو تمہارے سپرد کیا ہے تو روحانی تعلیم صرف انسانوں کے لئے ہی نہیں بلکہ جانوروں کے لئے بھی امن پیدا کرتی ہے.جسمانی نظام میں بھی خدا تعالیٰ کے نظام کے ماتحت ہی جانور پلتے ہیں.اس مادی عالم میں غلّہ انسانوں کے کام آتا ہے اور بھوسہ جانوروں کے کام آتا ہے مجھے ہمیشہ خیال آتا ہےکہ اگر غلّہ ہی غلّہ پیدا ہوتا تو لوگ جانوروں کو بھوکا مار دیتے مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھو کہ اُس نے آدمی کا پیٹ چھوٹا بنایا اور جانور کابڑا بنایا.دوسری طرف اسی مناسبت سے غلّہ تھوڑا ہوتا ہے اور بھوسہ بہت زیادہ ہوتاہے اگر غلّہ ہی غلّہ ہوتا تو سب کچھ انسان کھا
Page 204
جاتے اورجانور بھوکے مر جاتے.یہی روحانی نظام کی کیفیت ہے اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے روحانی نظام قائم نہ کیا جاتا تو بڑے بڑے لوگ ساری دنیا کے حقوق دبا کر بیٹھ رہتے اور غریبوں کو لوٹ لیتے جیسے آجکل ہو رہا ہے کہ جرمنی چاہتا ہے ساری دنیا کی دولت میں کھینچ لوں.انگلستان اور امریکہ والے چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں میں سب دنیاکی دولت ہو وہ دوسروں کو اُن کے حقوق تو دیتے ہیں مگر اپنا ساتھی یا دوست ہونے کی وجہ سے دیتے ہیں انسان ہونے کی حیثیت سے نہیں دیتے مگر اللہ تعالیٰ جس نظام کو قائم کرتا ہے اس میں چھوٹے بڑے.امیر غریب ماتحت اور افسر سب کے حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے اور ہر ایک کو اُس کا جائز حق دلایا جاتا ہے.فَاِذَا جَآءَتِ الطَّآمَّةُ الْكُبْرٰى ٞۖ۰۰۳۵ پس جب وہ بڑی آفت آئے گی.حل لغات.اَلطَّامَّۃُ:.الطَّامَّۃُ طَمَّ سے ہے اور طَمَّ الْمَآئُ کے معنے ہوتے ہیں غَمَرَ یعنی کسی چیز کو پانی نے ڈھانپ لیا.طَمَّ فُلَانٌ اَلْاِنَائَ کے معنے ہوتے ہیں مَلَأَہٗ اُس نے برتن کو پانی سے بھر دیا.طَمَّ الشَّیْئُ کے معنے ہوتے ہیں عَلَا وَغَلَبَ وہ چیز اونچی ہو گئی اور غالب آگئی.اور طَمَّ الْاَمْرُ کے معنے ہوتے ہیں تَفَاخَمَ وہ کام بہت زیادہ اور عظیم الشان صورت اختیار کر گیا.(اقرب) اَلطَّامَّۃُ: اَلدَّاھِیَۃُ تَغْلِبُ مَا سِوَاھَا قِیْلَ لَھَا ذَالِکَ لِاَنَّھَا تَطَمُّ کُلَّ شَیْ ئٍ اَیْ تَعْلُوْہُ وَ تُغَطِّیْہِ یعنی طَامَّۃ اس سخت مصیبت کو کہتے ہیں جو باقی تمام مصیبتوں پر غالب آجائے اور جس کی وجہ سے اور تمام مصیبتیں انسان کو بُھول جائیں.(اقرب) تفسیر.یہاں خدا تعالیٰ نے احیاء روحانی اور بعث بعد الموت کے متعلق ایک اور دلیل پیش کی ہے اور بتایا ہے کہ جو خدا اس دنیا میں اتنا بڑا انقلاب پیدا کر سکتا ہے جو کسی انسانی قیاس اور واہمہ میں بھی نہیں آسکتا تھا وہ تمہیں مرنے کے بعد کیوں زندہ نہیں کر سکتا یا کیوں تم اس سے یہ نتیجہ نہیںنکال لیتے کہ اسلام کے غلبہ کے متعلق جو کچھ کہا جارہا ہے وہ بھی بالکل صحیح اور درست ہے.پہلے فرمایا تھا فَاِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَّاحِدَةٌ.فَاِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِکہ ایک دن اچانک ہم کفار کو میدانِ جنگ کی طرف ہنکا کر لے جائیں گے اور یہ سب کے سب وہاں ننگے ہو جائیں گے اس میں جنگ بدر کی طرف اشارہ تھا اور
Page 205
بتایا گیا تھا کہ ابھی تو تمہیں ایک ہی دھکّا لگا ہے.آگے آگے دیکھو کہ تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے.چنانچہ اس کے بعد تَتْبَعُھَا الرَّادِفَۃُ کے مطابق پے در پے کئی جنگیں ہوئیں اور رادفہ کے بعد رادفہ آئی.اب فرماتا ہے ان متواتر اور مسلسل جنگوں کے بعد ایک طامۂ کبریٰ کا دن آنے والا ہے.طامہ کبریٰ سے مراد اس دنیا کا عذاب اس طامۂ کبریٰ سے مراد فتح مکہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب وہ طامۂ کبریٰ آئے گی تو اُس دن تمہیں اپنے اعمال کی حقیقت خوب اچھی طرح معلوم ہو جائے گی.اس سے صاف پتہ لگتا ہے کہ یہاں دنیا کے عذاب کا ہی ذکر ہو ر ہاہے اگلے جہان کی قیامت اس سے مراد نہیں.کیونکہ یہ وہ عذاب ہیں جن کے آہستہ آہستہ آنے کا ذکر ہو رہا ہے پہلے یوں ہو گا.پھر یوں ہو گا اور پھر طامۂ کبریٰ کا دن آئے گا.مگر اُخروی قیامت تو وہ ہےجو اچانک آجائے گی پس یہاں رجفۂؔ اور رادفہؔ اور طامۂ کبریٰؔ وغیرہ سے مراد وہ عذاب ہیں جو کفار پر آنے والے تھے.چنانچہ پہلے بدر کی جنگ ہوئی اور پھر رادفہ کے بعد رادفہ آئی اور آخر مکہ فتح ہوا اور اسلام کا غلبہ ہو گیا.اگر ان آیات کو اگلے جہان پر چسپاں کیا جائے تو پھر ہم یہ معنے کریں گے کہ مضمون کو یہاں دہرایا گیا ہے اور مختلف عذابوں کے نزول کے بعد فیصلے کا جو آخری دن آنے والا تھا اور جس میں عذاب نے اپنے کمال کو پہنچ جانا تھا اُس کو تامۂ کبریٰ قرار دیا گیا ہے لیکن بہرحال پہلا اشارہ دنیوی عذابوں کی طرف ہی ہے.يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ مَا سَعٰى ۙ۰۰۳۶ جس دن انسان اپنے کئے کو یاد کرے گا.تفسیر.طامہ کبریٰ کے آنے کا وقت.جس دن انسان یاد کرے گا اُس کو جو اُس نے کوشش کی تھی یعنی انسان کو اپنے اعمال نظر کے سامنے رکھتے ہوئے یاد آجائے گا کہ اُس نے یہ کچھ کیا تھا اور اُسے یہ کچھ کرنا چاہیے تھا.جب بھی انسان کے کسی بُرے فعل کا کوئی نتیجہ نکلتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اب مُجھے اُس کام کی وجہ سے سزا ملنے لگی ہے تو اُس وقت اُس کے دل میں یہ خیال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ اگر میں فلاں وقت یوں کرتا تو یوں ہو جاتا.اگر اس طرح کام کرنے کی بجائے اُس طرح کرتا تو اور نتیجہ نکلتا.یہ بات انسانی فطرت میں داخل ہے اور اللہ تعالیٰ اسی نے انسانی فطرت کا اس جگہ نقشہ کھینچا ہے.میں سمجھتا ہوں دنیا میں ایک شخص بھی ایسا نظر نہیں آسکتا جو اپنے کاموں کے اچھے یا بُرے نتیجہ کے وقت یہ سوچتا
Page 206
نہ ہو کہ اگر میں اس طرح کرتا تو یہ نتیجہ نکلتا.بچوں کو دیکھ لو جب وہ امتحان میں فیل ہو جائیں تو وہ سوچنے لگتے ہیں کہ اگر ہم کھیل کود میں اپنے دن ضائع نہ کرتے تو کبھی فیل نہ ہوتے اور اگر پاس ہو جائیں تو پھر وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم فلاں فلاں کھیل میں اپنا وقت ضائع نہ کرتے تو موجودہ نمبروں سے بہت زیادہ نمبر حاصل کرتے.غرض آخری نتیجہ کے وقت انسان ضرور اپنے گزشتہ اعمال پر نظر دوڑاتا اور اُن کو یاد کر کے سوچتا ہے.اگر اُسے ناکامی ہو تو وہ حسرت کرتا ہے کہ میں نے کیوں ایسے کام کئے جن سے مجھے ناکامی ہوئی.اور اگر اُسے کامیابی ہو تو پھر وہ یہ سوچنے لگ جاتا ہے کہ اگر میں اس سے بھی زیادہ کام کرتا تو نتیجہ اور بھی شاندار نکلتا اللہ تعالیٰ اسی انسانی فطرت کا نقشہ کھینچتے ہوئے اس جگہ فرماتا ہے کہ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ مَا سَعٰى اسلام اور کفر کا آخری فیصلہ جب فتح مکہ کے دن ہو گا تو اُس دن انسان اپنے کاموں کو یاد کرے گا اور جیسا جیسا کسی نے اسلام سے سلوک کیا ہو گا وہ اُس کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا.فتح مکہ کے بعد کفار و مشرکین کے دل میں کس طرح بار بار یہ خیال آتا ہو گا کہ اگر ہم رسول کریم صلے اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کی مخالفت نہ کرتے تو کیا اچھا ہوتا.جب رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں داخلہ کے وقت یہ اعلان کیا ہو گا کہ جو شخص اپنے گھر کے دروازے بند کر کے اندر بیٹھ رہے گا اُسے کچھ نہیں کہا جائے گا.اُس وقت وہ لوگ جو مسلمانوں کو بڑی بڑی سخت اذیّتیں پہنچایا کرتے تھے کس طرح اندر گھروںمیں بیٹھے ہوئے سوچتے ہوں گے کہ اگر ہم اسلام کی مخالفت نہ کرتے تو آج ہم بھی گھوڑے دوڑاتے ہوئے مکہ کی گلیوں میں پھر رہے ہوتے اور مکانوں کے اندر چھپ کر نہ بیٹھے ہوتے.حضرت عمرؓ اپنی خلافت کے ایام میں ایک دفعہ حج کرنے کے لئے مکہ میں آئے تو مکّہ کے بڑے بڑے رئوساء آپ کے ملنے کے لئے گئے.خاندانی لحاظ سے حضرت عمرؓ حضرت ابوبکرؓ سے بڑے تھے اور مکہ میں اُن کا خاندان بہت مشہور تھا.جب آپ حج کے لئے آئے تو مکہ کے رئوسا نے سمجھا کہ اب چونکہ ایسا شخص خلیفہ ہے جو ہمارے خاندانوں کی عظمت سے خوب واقف ہے اس لئے اب ہمارا خاص طور پر اعزاز کیا جائے گا اور ہماری خاندانی روایات کو قائم رکھا جائے گا.چنانچہ وہ حضرت عمرؓ سے ملنے کیلئے آئے اور آپ نے اُن سے باتیں شروع کر دیں.وہ ابھی باتیں ہی کر رہے تھے کہ ایک حبشی اور غلام مسلمان جس کو قریش کے بڑے بڑے سردار مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا کرتے تھے آپہنچا اور اُس نے حضرت عمرؓ کو السلام علیکم کہا.حضرت عمرؓ رئوسا مکہ سے کہنے لگے ان کو ذرا جگہ دے دو.اور خود پیچھے ہٹ جائو چنانچہ وہ پیچھے ہٹ گئے اور حضرت عمرؓ نے اُن سے باتیں شروع کر دیں.اتنے
Page 207
میںایک دوسرا مسلمان سابق غلام آگیا.پھر تیسرا اور پھر چوتھا آیا.خدا تعالیٰ کی قدرت ہے کہ یکے بعد دیگرے سات مسلمان جو کسی زمانہ میں کفار مکہ کے غلام ہوا کرتے تھے آ پہنچے.شاید اللہ تعالیٰ اس ذریعہ سے اُن کو سبق دینا چاہتا تھا.ان میں سے ہر ایک جب مکان میں داخل ہوتا تو حضرت عمرؓ ان سے فرماتے ذرا پیچھے ہٹ جائواور ان کو بیٹھنے کے لئے جگہ دو.چنانچہ ہر مسلمان غلام کے آنے پر وہ پیچھے ہٹتے چلے گئے یہاں تک کہ جوتیوں میں جا پہنچے اور تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے اُٹھ کر باہر آگئے.باہر نکل کر انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ کچھ دیکھا آج ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوا ہے اور مجلس میں ہماری کتنی بڑی ذلّت کی گئی ہے.ہم وہ ہیںجو بادشاہوں کے درباروں میں بھی عزت کی جگہ حاصل کرتے تھے مگر آج ایک ایک حبشی غلام کو جو ہمارے باپ دادا کی خدمتیں کیاکرتے تھے ہمارے مقابلہ میں عزت دی گئی اور ہمیں ہر دفعہ پیچھے ہٹایا گیا یہاں تک کہ ہم جوتیوں میں جا پہنچے.یہ کتنی بڑی ذلّت ہے جو آج ہماری ہوئی ہے.اِس پر اُنہی میں سے ایک شخص جو زیادہ سمجھدار تھا بولا کہ تم جو کچھ کہتے ہو ٹھیک ہے مگر تم یہ بھی تو سوچو کہ اس میں کس کا قصور ہے عمرؓ کا قصور ہے یا ہمارا اپنا قصور ہے؟ جب رسول کریم صلے اللہ علیہ وآلہٖ وسلم نے دعویٰ فرمایا تو اُس وقت یہی حبشی غلام تھے جو آپ پر ایمان لائے مگر ہمارے باپ دادا نے آپ کی مخالفت کی اور شدید مخالفت کی.پس اگر اُن کو زیادہ عزت سے بٹھایا گیا ہے اور ہمیں ان کے آنے پر پیچھے بٹھایا گیا ہے تو یہ بالکل درست ہوا ہے وہ اسی بات کے مستحق تھے کہ ان کو عزت کا مقام دیا جاتا اور ہم اس بات کے مستحق تھے کہ ہم کو پیچھے ہٹایا جاتا کیونکہ ہمارے باپ دادا نے اسلام کی مخالفت کی اور رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے محروم رہے.انہوں نے کہا یہ تودرست ہے مگر کیا اس ذلّت کو دور کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں.اور کیا ایسا کوئی طریق نہیں ہے جس سے اس رسوائی کا ازالہ ہو سکے؟ آخر سب نے سوچنے کے بعد فیصلہ کیا کہ ہمیں تو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی چلو حضرت عمرؓ سے ہی دریافت کریں کہ اس کا کیا علاج ہو سکتا ہے.چنانچہ وہ حضرت عمرؓ کے پاس آئے اُس وقت تک مجلس برخاست ہو چکی تھی اور دوسرے لوگ واپس جا چکے تھے.وہ السلام علیکم کہہ کر بیٹھ گئے اور انہوں نے حضرت عمرؓ سے کہا آج ہمارے ساتھ جو ہوا وہ آپ نے دیکھ لیا ہم اُسی کے متعلق کچھ کہنے کے لئے حاضر ہوئے ہیں.حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ میں معذرت کرتا ہوں کیونکہ میرے لئے سخت مجبوری تھی.یہ وہ لوگ تھے جن کا رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم ادب کیا کرتے تھے اور جن کا ادب میرا آقا کرتا رہا میرا بھی فرض ہے کہ میں اُن کا لحاظ کروں اور اُنہیں دوسروں پر ترجیح دُوں مجھے افسوس ہے کہ اس سے آپ کو تکلیف ہوئی مگر میرے لئے اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا.انہوں نے کہا ہم سمجھ گئے ہیں کہ آپ نے جو کچھ کیا درست کیاہم صرف یہ دریافت کرنا چاہتے ہیں کہ کیا اس ذلّت کو دُور کا
Page 208
کوئی طریق نہیں؟ اگر کوئی علاج ہو تو بتایا جائے کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ یہ ذلّت کا داغ ہم پر رہے.وہ رئوساء جو حضرت عمرؓ کے پاس آئے تھے اُن میں سے کسی کا باپ حضرت عمرؓ کا دوست تھا.کسی کے چچا سے اُن کے تعلقات تھے.کوئی ان سے رشتہ داری کےتعلقات رکھتا تھا اور کسی سے اُنہیں ذاتی طور پر اُنس اور تعلق تھا.حضرت عمرؓ جانتے تھے کہ ان کا خاندانی لحاظ سے کس قدر شہرہ تھا.کس قدر رُعب اور شوکت یہ لوگ رکھتے تھے اور کس طرح مسلمانوں کو تحقیر کی نگاہوں سے دیکھا کرتے تھے.جب انہی خا ندانوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے حضرت عمرؓ سے یہ کہا کہ ہمیں کوئی ایسا طریق بتایا جائے جس سے یہ ذلّت کا داغ ہم سے دُور ہو جائے تو حضرت عمرؓ کو اُن کی پرانی حشمت یاد آگئی اور ان کی آنکھوں میں آنسو آگئے اور غلبۂ رقت کی وجہ سے وہ کوئی جواب نہ دے سکے صرف انہوں نے انگلی اٹھائی اور شام کی طرف اشارہ کر دیا.جس کا مطلب یہ تھا کہ ادھر اسلام کی فتح کے لئےایک جنگ ہو رہی ہے اگر تم اس ذلّت کے داغ کو دور کرنا چاہتے ہو تو جائو اس جنگ میں شامل ہو کر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دو.وہ اس جواب کو سمجھ گئے چنانچہ وہ وہاںسے اٹھے اوربغیر اس کے کہ اپنے گھروں کو واپس جاتے سب کے سب شام کی طرف چلے گئے اور تاریخ بتاتی ہے کہ پھر اُن میں سے ایک شخص بھی زندہ واپس نہ آیا.بلکہ سب کے سب اس جگہ شہید ہو گئے.تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ مَا سَعٰى اس دن ہر انسان سوچے گا کہ وہ کیا کچھ کرتا رہا ہے صحابہؓ نے بھی جب ان ترقیات اور انعامات کو دیکھا ہو گا تو اُن کے دلوں میں بار بار یہ خیال آتا ہو گا کہ کاش ہم زیادہ قربانیاں کرتے.کاش ہم زیادہ اپنے اخلاص کا ثبوت دیتے.وہی قربانیاں جن کو وہ پہلے بڑا سمجھا کرتے تھے.وہی چندے جن کو وہ پہلے غیر معمولی قرار دیا کرتے تھے.انہی قربانیوں اور انہی چندوں کے متعلق اُن کو خیال آتا ہو گا کہ ہم نے تو کچھ بھی نہ کیا کاش ہم اس سے زیادہ قربانیاں کرتے اور زیادہ انعامات حاصل کرتے.اسی طرح کفار کے دل میں حسرت پیدا ہوتی ہو گی کہ کاش ہم اسلام کی مخالفت نہ کرتے اور ان ترقیات میں ہم بھی حصہ دار بنتے پس يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ مَا سَعٰى کا یہ مطلب ہے کہ اُس دن ہر انسان کہے گا کہ کاش میں نے جو فلاں کام کیا ہے میں نہ کرتا یا کاش میں نے جو کچھ کیا ہےاس سے بڑھ کر کام کرتا قیامت کی صورت میں اس سے مراد ہو گی کہ دنیا کے اعمال کو یاد کر کے انسان حسرت کرے گا کہ کاش میں ایسا نہ کرتا.یا خوش ہو گا کہ میں نے بہت اچھا کیا.
Page 209
وَ بُرِّزَتِ الْجَحِيْمُ لِمَنْ يَّرٰى۰۰۳۷ اور جہنم اس کے لئے جو اُسے دیکھے گا ظاہر کر دی جائے گی.حل لغات.جَحِیْم.جَحِیْم جَحَمَ میں سے ہے.جَحَمَ النَّارَ کے معنے ہیں اَوْ قَدَ ھَا.آگ کو جلایا اور اَلْجَھِیْمُ کے معنے ہیں اَلنَّارُ الشَّدِیْدَۃُ التَّاَجُّجِ.سخت بھڑکنے والی آگ.اَلْمَکَانُ الشَّدِیْدُ الْحَرِّ.سخت گرمی والی جگہ.کُلُّ نَارٍ عَظِیْمَۃٍ فِیْ مَھْوَاۃٍ.ہر بڑی آگ جو گہری جگہ میں جل رہی ہو.اِسْمٌ مِنْ اَسْمَآئِ جَھَنَّم.نیز جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے (اقرب) تفسیر.لِمَنْ یَّریٰ اصل میں لِمَنْ یَّرَاہُ ہے یعنی جہنم اس شخص کے قریب کی جائے گی جو اس کو دیکھے گا اس کے یہ معنے تو نہیں ہو سکتے کہ بیناہی جہنم کا عذاب پائے گا اندھا شخص جہنم میں داخل نہیں کیا جائے گا اور جب اس کا یہ مفہوم نہیں تو لازمًا ہمیں کوئی اور مفہوم لینا پڑے گا.میرے نزدیک وَ بُرِّزَتِ الْجَحِيْمُ لِمَنْ يَّرٰىکے دو معنے ہیں.اوّلؔ یہ کہ جہنّم اس کے قریب کی جائے گی جس نے اُسے دیکھنا ہے یعنی اس میں پڑنے کا مستحق ہے.مومن اُسے دیکھیں گے بھی نہیں.آخر جو جہنّم کفّار کو نظر آرہی تھی وہ صحابہؓ کو کس طرح نظر آسکتی تھی وہ اسی میں اپنے لئے جنت دیکھ رہے تھے.گویا ایک ہی فعل کے نتیجہ میں کفار کو جہنم نظر آرہی تھی اور مومن اپنے لئے جنت دیکھ رہے تھے صحابہؓ جب گھوڑے دوڑاتے ہوئے مکّہ میں پھرتے ہوں گے تو انہیں اس جہنم کا خیال بھی کس طرح آسکتا تھا جس میں کفار مبتلا تھے.واقعہ ایک ہی تھا مگر کفار کے لئے وہ دوزخ بنا ہوا تھا اور صحابہؓ کے لئے جنت بن رہا تھا پس اس کے ایک معنے تو یہ ہیں کہ دوزخ اُسی شخص کے قریب کی جائے گی جو اس میں پڑنے کا مستحق ہے دوسرا شخص اُس دوزخ کو نہیں دیکھ سکے گا.دوسرے معنے یہ ہیں کہ لِمَنْ یَّرٰی سے مراد قلبی رویت ہے.ظاہری چیز یںایسی ہوتی ہے جن کو ہر شخص دیکھ سکتا ہے مثلاً آگ ہے جب جل رہی ہو تو کسی شخص کے اندر بصیرت کا مادہ ہو یا نہ ہو وہ اُسے دیکھ لے گا لیکن روحانی جہنم بسا اوقات موجود تو ہوتی ہے مگر نظر نہیں آتی.پس اس صورت میں دنیوی لحاظ سے لِمَنْ یَّریٰ کے یہ معنے ہوں گے کہ جہنم جس کی آنکھیں ہوں گی اُسے نظر آجائے گی اور جس کی آنکھیں نہیں ہوں گی اُسے نظر نہیں آئے گی.کیونکہ یہ وہ جہنم ہے جس کے دیکھنے کے لئے بصیرت کی ضرورت ہوتی ہے گویا اس رویت سے مراد ظاہری رویت نہیں بلکہ قلبی رویت ہو گی.مثلاً جب اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو بھیجتا ہے تو اُن کے آنے پر ایمان لانے والے آہستہ آہستہ بڑھنا
Page 210
شروع ہو جاتے ہیں اور انکار کرنے والے آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں.اب جس کی بصیرت ہوتی ہے وہ تو جانتا ہے کہ ایک قوم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تائید کا ہاتھ کام کرتا نظر آتا ہے اور دوسری قوم اس کی نصرت ومدد سے محروم ہو رہی ہے مگر جسے بصیرتِ روحانی حاصل نہیں ہوتی وہ کہہ دیتا ہے کہ یہ بھی کوئی بڑی بات ہے دنیا میں ہمیشہ قومیں گھٹتی بڑھتی ہیں یہ کوئی معجزہ نہیں کہ ایک قوم بڑھ رہی ہے اور دوسری گھٹ رہی ہے.گویا ایک قوم کو نظر آرہا ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ جہنم کی طرف جا رہے ہیں مگر انہیں اپنا جہنم نظر ہی نہیں آتا.اسی طرح یہاں بُرِّزَتِ الْجَحِيْمُ لِمَنْ يَّرٰى میں دیکھنے سے مراد قلبی رویت بھی لی جا سکتی ہے کہ جس کے اندر بصیرت پائی جاتی ہو گی صرف وہ اس جہنم کو قبل از وقت دیکھ سکے گا.چنانچہ رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم کے متعلق تاریخوں میں ذکر آتا ہے کہ آپ جب مکہ فتح کرنے کے لئے تشریف لائے تو اس وقت آپ نے صحابہؓ کو خاص طور پر ہدایت دے دی کہ اس موقعہ پر اپنی کسی شان کا اظہار نہیں کرنا.بلکہ جب ایک مسلمان افسر نے کہا کہ آج ہم مکّہ کی حرمت کو چاک کر کے رکھ دیں گے اور ان کفار کو بتادیں گے کہ انہوں نے ہم پر جومظالم کئے تھے اُن کا کیاانجام نکلا تو رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم نے فوراً اُسے اپنے عہدہ سے برطرف کر دیا اور اس کے بیٹے کو اس کی جگہ مقرر کر دیا (السیرۃ النبویۃ جلد۲ مصنّفہ احمد زینی زیر عنوان غزوۃ الفتح الاعظم وھو فتح مکہ شرفھا اللہ تعالیٰ) اس کی یہی وجہ تھی کہ رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے کہ آج کفّار کے لئے جو جہنم پیدا ہو گئی ہے وہ اُن کی طاقتِ برداشت سے بالکل باہر ہے اور آپ چاہتے تھے کہ اُن کی تکلیف کو جتنا بھی ہو سکے کم کیا جائے چنانچہ آپ نے حکم دے دیا کہ جو لوگ اپنے گھروں کے دروازے بند کر کے اندربیٹھ جائیں گے ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا(السیرة النبویۃ لابن ہشام ذکر الاسباب الموجبة المسیر الی مکة و ذکر فتح المکة).اس میں بھی دراصل یہی حکمت تھی کہ رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ اگر کفار اپنے گھروں سے باہر نکلے اور انہوں نے مسلمانوںکے ایک عظیم الشان لشکر کو مکّہ کی گلیوں میں پھرتے دیکھا تو ان کو سخت تکلیف ہو گی پس آپ نے چاہا کہ ان کے اس عذاب کو جس قدر ہلکا کیا جا سکے ہلکا کر دیا جائے.اسی لئے آپ نے یہ احکام دئے.ان معنوں کے لحاظ سے لِمَنْ یَّرٰی میں مومن بھی شامل ہیں لیکن پہلے معنوں کے لحاظ سےلِمَنْ یَّرٰی میںصرف کافر ہی شامل ہیں.درحقیقت رویت کئی قسم کی ہوتی ہے ایک رویت جسمانی ہوتی ہے.ایک رویت حسّی ہوتی ہے.ایک رویت عرفانی ہوتی ہے.ایک رویت علمی ہوتی ہے.ایک رویت قلبی ہوتی ہے.رویتِ حسّی یا رویتِ جسمانی کے لحاظ سے اس کے یہ معنے ہوں گے کہ صرف کافر ہی اس جہنم کو دیکھے گا کیونکہ وہی اس میں پڑنے کا مستحق ہے.اور رویتِ عرفانی
Page 211
یا رویتِ قلبی کے لحاظ سے مومن بھی اس رویت میں شامل ہو گا اور اُسے کفار کے اس دُکھ اور عذاب کا علم ہو گا جیسا کہ اوپر لکھا جا چکا ہےکہ بُرِّزَتِ الْجَحِيْمُ لِمَنْ يَّرٰى کے یہ معنے بھی ہیں کہ جہنم اس شخص کے لئے ظاہر کر دی جائے گی یا اُس شخص کو دکھا دی جائے گی جو اُسے دیکھنے کا مستحق ہے پس اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہاں دنیوی دوزخ کا ہی ذکر ہو رہا ہے کیونکہ اگلا دوزخ تو ہر ایک کو نظر آجائےگا اُس میں ایسی کسی شرط کی ضرورت نہیں ہے.فَاَمَّا مَنْ طَغٰى ۙ۰۰۳۸وَ اٰثَرَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَاۙ۰۰۳۹ پس جس نے سرکشی اختیار کی اور ورلی زندگی کو (آخرت پر) ترجیح دی تو فَاِنَّ الْجَحِيْمَ هِيَ الْمَاْوٰى ؕ۰۰۴۰ یقیناً جہنم (ہی اس کا) ٹھکانہ ہے.حَل لُغَات.اَلْمَاْوٰی.المَاْوٰی اِسْمٌ لِلْمَکَانِ الَّذِیْ یَاْوِیْ اِلَیْہِ.پناہ لینے کی جگہ (مفردات) تفسیر.پس وہ جس نے سرکشی کی اور ورلی زندگی کو اختیار کیا.اُخروی زندگی کا اُس نے کوئی خیال نہ رکھا وہ اُس دن کو دیکھ لے گا جب جہنم اُس کا ٹھکانہ ہو گی.ھِیَ الْمَأوٰیسے مراد ھِیَ الْمَأوٰی لَہٗ ہے کہ جہنم اُس کا مَأویٰ یعنی ٹھکانہ ہو گی.وَ اَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَ نَهَى النَّفْسَ عَنِ اور جس نے اپنے رب کے درجہ سے خوف کیا اور (اپنے) نفس کو گری ہوئی خواہشوں سے روکا تو یقیناً الْهَوٰى ۙ۰۰۴۱فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَاْوٰى ؕ۰۰۴۲ جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے.تفسیر.خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ کے دو معنے ہیں یہ بھی معنے ہیں کہ وہ اپنے رب کی شان اور رُتبہ سے ڈرتا ہے اور یہ معنے بھی ہیں کہ وہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے.گویا مَقَامَ رَبِّہٖ کے معنے مَقَامَہٗ اَمَامَ رَبِّہٖ کے بھی ہو سکتے ہیں اور یہ بھی ہو سکتے کہ وہ اُس کی شان اور عظمت کا خوف رکھتا ہے.یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو
Page 212
انسان کو گناہ سے بچاتی ہیں.خدا تعالیٰ کی شان اور عظمت کا خوف اعلیٰ مقام رکھنے والے مومن کو گناہوںسے بچاتا ہے اور مُجرم کے طور پر اُس کے سامنے پیش ہونے کا خوف ادنیٰ درجہ کے انسان کے لئے نجات کا موجب ہوتا ہے.بڑا مجرم تو کسی بات کی بھی پروا نہیں کرتا لیکن چھوٹا مجرم ڈرتا ہے کہ اگروہ اسی جرم کی حالت میں خدا تعالیٰ کے سامنے پیش ہوا تو اُس کو کیا جواب دے گا.لیکن بڑا مومن خدا تعالیٰ کے درجہ اور اُس کی شان کو دیکھ کر ڈرتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ مجھے اور بھی ترقی کرنی چاہیے میرا رب چھوٹے مقام پر رہنا پسندنہیں کرتا بلکہ وہ یہی چاہتا ہے کہ اُس کا بندہ اُس کی محبت اور قرب کے مراتب میں زیادہ سے زیادہ ترقی کرے.وَ نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى.ھَویٰ کے معنے ہوا و ہوس اور خواہشاتِ نفسانی کے بھی ہوتے ہیں اور ھَویٰ کے معنے گرنے کے بھی ہوتے ہیں.خدا تعالیٰ چونکہ بلند ہے اور ہوا وہوس کی پیروی انسان کو نیچے کی طرف لے جاتی ہے اس لئے جو شخص خواہشاتِ نفسانی کے پیچھے چلتا ہے وہ گر جاتا ہے اور گرنے کی وجہ سے خدا تعالیٰ سے بہت دور چلا جاتا ہے.یہ عجیب بات ہے کہ خدا تعالیٰ یہاں تلازم کے طور پر ایک ایسا لفظ لایا ہے جو خدا تعالیٰ سے دور جانے کی حقیقت کو بھی واضح کر رہا ہے کیونکہ ھَویٰ صرف خواہشاتِ نفسانی کو ہی نہیں کہتے بلکہ گرنے کو بھی کہتے ہیں اس میں درحقیقت اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ خواہشاتِ نفسانی کی پیروی انسان کو گرا دیتی ہے اور چونکہ اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے اس لئے ایساانسان اللہ تعالیٰ کے قرب کے راستوں سے دُور چلا جاتا ہے.يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسٰىهَاؕ۰۰۴۳ وہ تجھ سے اس گھڑی کے متعلق پوچھتے ہیں (کہ) اس کا آنا کب ہو گا فِيْمَ اَنْتَ مِنْ ذِكْرٰىهَاؕ۰۰۴۴ تجھے اس کے (آنے کے)ذکر سے کیا تعلق.حَلّ لُغَات.اَلسَّاعَۃُ.اَلْقِیَامَۃُ وَقِیْلَ اَلْوَقْتُ الَّذِیْ تَقُوْمُ فِیْہِ الْقِیَامَۃُ.السَّاعَۃَ کے معنے قیامت کے ہیں.اور بعض کہتے ہیں اس وقت کا نام سَاعَت ہے جس میں قیامت برپا ہو گی.اَلْبُعْدُ.دُوری اَلْمُشَقَّۃُ.تکلیف اَلْھَالِکُوْنَ.ہلاک ہونے والے لوگ.اس معنے میں سَاعَۃٌ سَائِع کی جمع سمجھی جائے گی.نیز
Page 213
اَلسَّاعَۃُکے معنے ہیں دن یا رات کا کوئی حصہ جس کو اُردو میں ایک گھڑی سے تعبیر کرتے ہیں.(اقرب) اَلْمُرْسٰی.اَلْمُرْسٰی اَرْسٰی سے اسم مفعول یا ظرف ہے اور اَرْسَی السَّفِیْنَۃَ کے معنے ہیں اَوْقَفَھَا عَلَی الْاَنْجَرِ.کشتی یا جہاز کو ان کی بندر گاہ پر لنگر انداز کر دیا یَسْئَلُوْنَکَ اَیَّانَ مُرْسٰھَا اَیْ مَتٰی وَقُوْعُھَا یعنی کب یہ پیشگوئیاں پوری ہوں گی.(اقرب) فِیْمَ اَنْتَ مِنْ ذِکْرٰھَا اس کے ذکر سے تجھے کیا.فِیْمَ اَنْتَ ایک محاورہ ہے جس کے معنے یہ ہوتے ہیں کہ تجھے اس سے کیا واسطہ.یعنی اس ذکر سے تیرا کیا تعلق کہ ایسا کب ہو گا اور کب یہ باتیں وقوع میں آئیں گی.تفسیر.پیشگوئیوں کے ظہور کا وقت بتایا جانا ضروری نہیں اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ پیشگوئیوں میں وقت کا بتانا ضروری نہیں ہوتا اور نہ اس سے اصل معاملہ کا کوئی تعلق ہوتا ہے جب تم پر عذاب ہی آنا ہے تو وہ دو دن پہلے آگیا یا دو دن بعد میں آگیا.اس سے اصل پیشگوئی پر کیا اثر پڑسکتا ہے.اس میں کوئی شبہ نہیں کہ پیشگوئیوںکے التواء میں بعض حکمتیں بھی ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اُن کو دوسری جگہ بیان بھی کیا ہے لیکن دشمن کا ہمیشہ یہ سوال رہتا ہے کہ جب ایک پیشگوئی کی گئی ہے تو اس کے پورا ہونے کی تاریخ بھی بتا دی جائے اور اس امر کا بھی اظہار کر دیا جائے کہ ایسا کب ہو گا مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہیں اس سے کیا واسطہ.جب پیشگوئی پوری ہو گئی تم میں سے ہر شخص کو نظر آجائے گا کہ خدا تعالیٰ نے جو کچھ کہا تھا وہ سچ ثابت ہوا.تمہیں اس کی تاریخ اور وقت اگربتا بھی دیا جائے تو تمیں اس سے کیا فائدہ ہو گا.حیرت آتی ہے کہ باوجود اس کے کہ قرآن کریم میں یہ ذکر آتا ہے کہ کفار یہ کہا کرتے تھے کہ جو پیشگوئیاں ہمارے سامنے کی جارہی ہیں وُہ کب پوری ہوں گی.ا ور باوجود اس کے کہ قرآن کریم میں یہ جواب دیا گیا ہے کہ پیشگوئیوں کے پورا ہونے کا وقت بتانا ضروری نہیں تم اگر ایک سال پہلے مرے یا ایک سال پیچھے مرے تمہارے لئے پیشگوئی کا وقت معلوم ہو جانے میں کوئی فائدہ نہیں تم نے تو بہرحال ہلاک اور تباہ ہونا ہے.مگر پھر بھی یہی اعتراض مخالفین کی طرف سے بار بار کیا جاتا ہے کہ جس عذاب کے آنے کی خبر دی گئی ہے وہ عذاب آئے گا کب.چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر مخالفین سلسلہ کی طرف سے بار بار یہی اعتراض کیا جاتا رہا کہ پیشگوئیاں مبہم رنگ میں کی جاتی ہیں اُن کے پورا ہونے کا وقت نہیں بتایا جاتا.حالانکہ یہ ایسا سوال ہے جس کے جواب سے مخالفین کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا.نبی کی اصل پیشگوئی تو یہ ہوتی ہے کہ میں کامیاب ہوں گا اور دنیا میرے مقابلہ میں ناکام رہے گی.یہ پیشگوئی ایسی ہے جس کے لئے کسی خاص وقت کی تعیین کی ضرورت نہیں ہوتی اور نہ اس میں کوئی ابہام ہوتا ہے.مخالف اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ تباہ ہوتے جا رہے ہیں اور نبی کو ماننے
Page 214
والے غالب آتے جا رہے ہیں مگر پھر بھی ان کی طرف سے یہ سوال جاری رہتا ہے کہ ہمیں وقت بتایا جائے ایسا کب ہو گا.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں اس سے کیا واسطہ.تم نے تو بہرحال تباہ ہونا ہے تمہیں اگر بتا بھی دیا جائے کہ تم مثلاً چار سال کے بعد تباہ ہو گے تو تمہیں کیا فائدہ ہو گا جب تباہی آئے گی اس وقت خود بخود پیشگوئی کی صداقت واضح ہو جائے گی.فرماتا ہے يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ یہ لوگ تجھ سے تیری اُن پیشگوئیوں کے بارہ میں جو اسلام کی ترقی اور کفر کے نابود ہونے کے متعلق ہیں سوال کرتے ہیں اور کہتے ہیں اَيَّانَ مُرْسٰىهَا ذرا یہ تو بتائیے کہ آپ کا جو بڑا بھاری جہاز کفار کی تباہی کے لئے آنیوالا ہے وہ کب لنگر انداز ہو گا؟اَيَّانَ مُرْسٰىهَامیں بظاہر تفخیم ہے لیکن درحقیقت اس سے مراد اُن کی تحقیر ہے کہ یہ بُلبلہ پھوٹے گا کب؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فِيْمَ اَنْتَ مِنْ ذِكْرٰىهَا تجھے اس سے کیا واسطہ اس ساعت نےتو تمہیں خدا تک پہنچانا ہے پھر تمہیں اس سے کیا کہ وہ تمہیں چند دن آگے پہنچا دیتی ہے یا پیچھے پہنچا دیتی ہے.ساعت کے متعلق تمہارا اس قدر اصرار کرنا اور کہنا کہ اس کی تاریخ بتلا دی جائے بالکل غلط ہے.یہ ساعت تو ایسی ہے جو لوگوں کو ایک دن خدا تک لے جائے گی.کسی کو مجرم بنا کر اور کسی کو مومن بتا کر.پس جب ایسا عظیم الشان تغیر پیدا ہونا ہے کہ خدا تعالیٰ کے سامنے کسی نے مجرم ہونے کی حیثیت میں پیش ہونا ہے اور کسی نے مومن ہونے کی حیثیت میں پیش ہو نا ہے تو پھر اس میں ابہام کون سا رہا اور تاریخ پوچھنے کی ضرورت ہی کیا رہی ہم تو تمہارے سامنے یہ خبر پیش کر رہے ہیں کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جب ہر شخص خدا تعالیٰ کے دربار میں پیش ہو گا کہ کچھ لوگ مجرموں کی حیثیت میں اس کے سامنے کھڑے ہوں گے اور کچھ لوگ مومنوں کی حیثیت میں اس کے سامنے کھڑے ہوں گے.کچھ لوگ انعام حاصل کریں گے اور کچھ لوگ عذاب کے مورد بنیں گے.اتنی بڑی خبر کے لئے کسی تاریخ معلوم کرنے کی ضرورت نہیں رہتی جب یہ بات وقوع میں آئی تمہیں خود بخود اس کی صداقت معلوم ہو جائے گی.اِلٰى رَبِّكَ مُنْتَهٰىهَاؕ۰۰۴۵ اس (کے وقت) کی انتہاء (کی تعیین) تو تیرے رب سے تعلق رکھتی ہے.تفسیر.ا س آیت میں پیشگوئیوں کے وقوع کی تاریخ معلوم کرنے کی لغویت بتائی ہے اور بتایا ہے کہ وقت معلوم کرنے سے فائدہ کیا.اصل غرض تو یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کا جلال ظاہر ہو جائے سو وہ ایک دن ظاہر ہو جائے گا
Page 215
اور وہ گھڑی انسانوں کو خدا تعالیٰ تک لے جائے گی.اصل اہمیت تو اسی امر کی ہے سو یہ ہم نے بتا دیاہے.چنانچہ دیکھ لو مکّہ کے متعلق جب یہ پیشگوئی کی گئی کہ رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم ایک دن اس کو فتح کریں گے.مسلمان غالب آئیں گے.کفار تباہ ہوں گے اور وہ جن کو غلام سمجھ کر مبتلائے آلام کیا جاتا تھا بڑی بڑی عزتیں حاصل کریں گے تو اس کے بعد بھلا یہ کیا سوال رہ جاتا ہے کہ یہ بات جمعہ کوہو گی یا ہفتہ کو.اس سال ہو گی یا اگلے سال ہوگی؟ دوسری صورت میں جب ان آیات کو اُخروی زندگی کے متعلق سمجھا جائے تو اس کےیہ معنے ہوں گے کہ تقدیر کے دھاگے تو اس کے ہاتھ میں ہیں اور تمام اسباب اس کے قبضہ و تصرّف میں ہیں اس لئے وہ جب چاہے گا اس کا ظہور کرے گا یعنی جو کچھ ہوتا ہے الٰہی منشاء اور اس کے ارادہ کے ماتحت ہوتا ہے بندوں کا اس میں کچھ دخل نہیں ہوتا.پس جبکہ اس نے تمام تقدیریں اپنے قبضہ میں رکھی ہوئی ہیں تو پھر جب چاہے گا اس ساعت کو ظاہر کر دے گا چنانچہ قرآن کریم میں دوسری جگہ وضاحت کر دی گئی ہے کہ اِنَّ اللّٰہَ عِنْدَہٗ عِلْمُ السَّاعَۃِ (لقمان :۳۵)قیامت کے دن کا علم سوائے خدا کے اور کسی کو نہیں.یہی بات اس جگہ بیان کی گئی ہے کہ اِلٰى رَبِّكَ مُنْتَهٰىهَا سارے تغیرات تو ہم نے کرنے ہیں تمہاراس سے کیا واسطہ ہے.اِنَّمَاۤ اَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَّخْشٰىهَاؕ۰۰۴۶كَاَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا ُو تو صرف اُس کو جو اس (آفت) سے ڈرتا ہے ہوشیار کرنے والا ہے.وہ جس دن اُسے دیکھیں گے (ان کی حالت لَمْ يَلْبَثُوْۤا اِلَّا عَشِيَّةً اَوْ ضُحٰىهَاؒ۰۰۴۷ ایسی ہو گی کہ) گویا وہ صرف ایک شام یا اس کی صبح (اس دنیا میں) رہے ہیں.حل لغات.مُنْذِرٌ مُنْذِرٌ اَنْذَرَ سے اسم فاعل کا صیغہ ہے اور اَنْذَرَ کے معنے ہوتے ہیں کسی امر کی حقیقت سے اُسے آگاہ کیا اور اس امر کے نتائج کےظاہر ہونے سے پہلے اُسے ہوشیار کر دیا.نیز اس کے معنے یہ بھی ہوتے ہیں کہ خبر پہنچاتے ہوئے خوب ہوشیار کر دیا (اقرب) پس مُنْذِرٌ کے معنے ہوں گے.خبردار کرنے والا.خطرے سے خوب ہوشیار کرنے والا.اَلْعَشِیُّ اٰخِرُ النَّھَارِ.دن کا آخری حصہ.وَقِیْلَ مِنْ صَلَاۃِ الْمَغْرِبِ اِلَی الْعَتَمَۃِ اور بعض کے نزدیک مغرب سے لے کر عشاء تک کا وقت عَشِیُّ کہلاتا ہے.(اقرب)
Page 216
تفسیر.فرماتا ہے تُو توصرف ایک منذر ہے اُس شخص کے لئے جو آنے والے عذاب سے ڈرتا ہے ہاں ہم صرف ایک بات بتا دیتے ہیں اور وہ یہ کہ جب وہ عذاب آئے گا تو لَمْ يَلْبَثُوْۤا اِلَّا عَشِيَّةً اَوْ ضُحٰىهَا وہ اتنے شدید عذاب کا دن ہو گا کہ انہیں اپنی ساری گزشتہ ترقی یُوں معلوم ہوگی جیسے صرف چند گھنٹے رہی.یہ عذاب کی شدّت کی طرف اشارہ ہے کیونکہ جب انسان کو کوئی شدید تکلیف پہنچے تو اُسے اپنے آرام اور راحت کی گھڑیاں بالکل چھوٹی معلوم ہوتی ہیں اور انسان یوں سمجھتا ہے کہ وہ ہمیشہ دُکھ میں ہی مبتلا چلا آرہا ہے آرام اُسے کبھی نصیب نہیں ہوا.پس فرماتا ہے جب وہ عذاب آئے گا تو کفار اپنی ساری گزشتہ شان وشوکت کو بھول جائیں گے اور انہیں اپنی ترقی کا دَور یوں معلوم ہو گا جیسے وہ چند گھنٹے کا تھا.چنانچہ دیکھ لو جب عرب کی تاریخ بیان کی جاتی ہے تو پانچ دس صفحوں میں عرب کی تمام پہلی تاریخ آجاتی ہے اور باقی دس ہزار صفحوں میں اسلامی حالات کو بیان کرنا پڑتا ہے حالانکہ پُرانی تاریخ کا زمانہ بہت لمبا تھا مگر جب اسلام کا ظہور ہوا تو وہ واقعات ہی مٹ گئے.وہ حالات ہی نظروں سے اوجھل ہو گئے.اب جس کی بھی نظر پڑتی ہے اسلامی دَور پر ہی پڑتی ہے پہلے زمانہ کے حالات پر نہیں پڑتی چنانچہ تاریخ کی کتابیں لکھنے والے چند صفحوں میں سارے عرب کی تاریخ لکھ دیتے ہیں اور پھر ہزاروں صفحات رسول کریم صلے اللہ علیہ وآلہٖ وسلم اور مسلمانوں کے حالات کے لئے وقف کر دیتے ہیں پس جس طرح انسانی زندگی کے مقابلہ میں عشیّہ اور ضحی کا نہایت قلیل حصہ ہوتا ہے اسی طرح فرماتا ہے اسلام کے مقابلہ میں تمہاری تاریخیں مٹ جائیں گی.تمہاری عظمتیں جاتی رہیں گی.تمہاری شان وشوکت کی داستانیں دنیا سے محو ہو جائیںگی اور کوئی شخص تمہارے باپ دادا کے کارناموں بلکہ ان کے ناموں تک سے بھی واقف نہیں رہے گا.یہ ویسی ہی بات ہے جیسے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے الہامًا فرمایا کہ ینْقَطِعُ مِنْ اٰبَآئِکَ وَیُبْدَأُ مِنْکَ (حقیقۃ الوحی روحانی خزائن جلد ۲۲ صفحہ ۷۹،تذکرہ صفحہ ۶۵) یعنی تیرے آباء کا ذکر منقطع کر دیا جائے گا اور تجھ سے آئندہ تاریخ کا ابتدا ء کیا جائے گا چنانچہ دیکھ لو اگر کوئی تاریخ لکھنا چاہے تو وہ چند صفحوں میں ہی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے تمام آبائو اجداد کے حالات ختم کر دے گا اور اصل تاریخ اس وقت سے شروع کرے گا جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ذکر آئے گا.حالانکہ دنیوی لحاظ سے وہ بہت بڑی شان رکھتے تھے مگر باوجود اس کے کہ اپنے زمانہ مین وہ بہت بڑی عظمت رکھتے تھے اللہ تعالیٰ نے یہی فیصلہ کیا کہ آئندہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام سے تاریخ کی ابتدا کرے اور آپ کے آباء کے ذکر کو منقطع کر دیا جائے.اسی طرح فرماتا لَمْ يَلْبَثُوْۤا اِلَّا عَشِيَّةً اَوْ ضُحٰىهَا ہم ان کی تاریخ کو اتنا چھوٹا کر دیں گے اور آنحضرت صلے اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کو ان کے مقابلہ میں اتنی عظمت دیں گے کہ عرب کی ساری تاریخ
Page 217
محمدصلے اللہ علیہ وسلم کی عشیّہ یا ضحی جتنی رہ جائے گی.عَشِیّۃ کو پہلے اور ضُحٰیکو بعد میں بیان کر نے کی حکمت ضُحٰھَا کی ضمیر عَشِیَّۃ کی طرف جاتی ہے اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دوپہر تو پہلے آتی ہے اور شام بعد کو پھر اس جگہ عَشِیّۃ کو پہلے اور ضحی کو بعد میںکیوں بیان کیا گیا ہے؟ وہ لوگ جو قرآن کریم کی حکمتِ کاملہ اور فصاحت فوق البشریّہ پر پوری آگاہی نہیں رکھتے کہہ دیں گے کہ قافیہ کے لئے ایسا کر دیا گیا ہے چونکہ پہلی آیتوں کا خاتمہ مُرْسٰھَا.ذِکْرٰھَا مُنْتَھٰھَا.یَخْشٰھَا کے الفاظ پر ہوا تھا وزن ملانے کے لئے یہاںبھی عَشِیَّۃ کو پہلے کر دیا گیا ہے اور ضُحٰھَا کو بعد میں رکھ دیا گیا ہے.مگر فصاحت قرآنیہ اور اس کے معجزۂ بیان کو مدِّ نظر رکھتے ہوئے یہ جواب صحیح نہ ہو گا.قرآن کریم صرف لفظی رعایت کی وجہ سے مضمون کو کبھی نہیں بگاڑتا.اصل بات یہ ہے کہ دن یا بعض حصّۂ دن تھوڑے وقت کے بیان کرنے کے لئے قرآن کریم میں آتا ہے جیسے کہ سورہ مومنون آیت ۱۱۴ میں کفار کی نسبت آیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم یَوْمًا اَوْبَعْضَ یَوْمٍ دنیا میں رہے.وہی محاورہ دوسرے الفاظ میں اس جگہ بیان ہوا ہے دن کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے چوبیس گھنٹوں کے وقت کو بھی دن کہتے ہیں اور صبح سے شام تک کے وقت کو بھی دن کہتے ہیں ان آیات میں صبح سے شام تک کے وقت کا نام دن رکھا گیا ہے اور صبح سے شام تک کے وقت میں لمبا وقت وہ ہے جو شام کو ختم ہو اور چھوٹا وقت وہ ہے جو دوپہر کو ختم ہو.چونکہ اس جگہ یہ امر بتانا مقصود ہے کہ کفّار کی سب ترقیات ہیچ اور لغو تھیں کیونکہ انجام سزا اور عذاب کی صورت میںہوا.اس لئے عَشِيَّةً اَوْ ضُحٰىهَا کہہ کر بتایا گیا ہے کہ منکرین اسلام کا انجام دو طرح کا ہو گا.بعض دشمن تو وہ ہیں جن کی مثال ایسی ہو گی کہ وہ اپنی دنیوی ترقیات کا زمانہ ختم کر چکے ہیں اور اپنی عمر کی شام کو پہنچ چکےہیں اور وہ اب اسلام سے ٹکر ا کر تباہ ہو جائیں گے لیکن بعض ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنی دنیوی ترقی کا زمانہ دیکھا بھی نہیں اب اُن پر جوانی کا زمانہ آیا ہے وہ بھی بوجہ اسلام سے ٹکرانے کے تباہ ہو جائیں گے گویا یہ لوگ شام کا مُنہ بھی دیکھنے نہ پائیں گے اپنی قومی زندگی کی دوپہر کوہی ہلاک ہو کر عبرت بن جائیں گے.یہ وہی مضمون ہے جو کسی شاعر نے ان الفاظ میں باندھا ہے ؎ پھول تو دو دن بہارِ جانفزا دکھلا گئے حسرت اُن غنچوں پہ ہے جو بِن کھلے مرُجھا گئے غرض جب تباہی کا ذکر کرنا ہو تو بلاغت کا مطالبہ ہوتا ہے کہ پہلے لمبے زمانہ کا ذکر کیا جائے پھر چھوٹے کا.اس
Page 218
لئے یوں فرمایا کہ ان لوگوں میں سے بعض تو شام تک پہنچے اور بعض دوپہر تک ہی پہنچے تھے کہ ہلاک ہوگئے.اسی مناسبت سے جہاں یوم اور بعض یوم کے الفاظ استعمال کئے ہیں وہاں بھی یوم کا ذکرپہلے کیا ہے اور بعض یوم کا بعد میں.پس ضُحٰھَا کو بعد میں قافیہ کی غرض سے بیان نہیں کیا.بلکہ اس لئے بعد میں بیان کیا ہے کہ ضحی چھوٹے عرصہ پر دلالت کرتا ہے اور اس مقام پر لمبے عرصہ کا ذکر پہلے اور چھوٹے کا بعد میں ہی مناسب ہے کیونکہ لمبا عرصہ گزارنا چھوٹے عذاب پر دلالت کرتا ہے اور تھوڑا عرصہ گزارنا بڑے عذاب پر.اور ترتیب مناسب یہی ہے کہ جب عذاب کا ذکر ہو تو پہلے چھوٹے عذاب کا ذکر کیا جائے اور بعد میں بڑے عذاب کا.تا تدریج و ترتیب مد نظر رہے.بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اسلام کی عظمت اور اس کی ترقی کی طرف اشارہ کیا ہے اور بتایا ہے کہ کفر کا زمانہ بالکل سُکڑ جائے گا اور اسلام کا زمانہ اتنا پھیلے گا.اتنا پھیلے گا کہ اسلامی ترقی کے زمانہ کےمقابلہ میں کفار کو اپنا زمانہ ایسا ہی نظر آئے گا جیسے انسانی عمر کے مقابلہ میں ایک عشیّہ یا ضحی کی حیثیت ہوتی ہے.خ خ خ خ
Page 219
سُوْرَۃُ عَبَسَ مَکِّیَّۃٌ سورۃ عبس.یہ سورۃ مکّی ہے وَھِیَ اثْنَتَانِ وَ اَرْبَعُوْنَ آیَة دُوْنَ الْبَسْمَلَةِ وَ فِیْھَا رُکُوْ عٌ وَّاحِدٌ اور اس کی بسم اللہ کے بغیر بیالیس آیتیں ہیںاور ایک رکوع ہے.۱؎ سورۃ عبس مکّی ہے ۱؎ سورۃ عبس مکی سورۃ ہے اور بہت ہی ابتدائی سورتوں میں سے ہے(روح المعانی تفسیر سورۃ عبس).یوروپین مصنّفین بھی اس بات پر متفق ہیں کہ یہ ابتدائی مکّی سورۃ ہے چنانچہ نولڈک NOLDEKE جرمن مستشرق ابتدائی زمانہ کی بھی ابتدائی سورتوں میں اس کو شامل کرتاہے.میور MUIRبھی اِسے اُن پہلی سورتوں میں سے قرار دیتا ہے(Wherry Commentery on Quran vol.4 pg 218) جنہیں کفار پر ظاہر کیا گیا یعنی پہلی چند سورتوں کے متعلق مستشرقین کا خیال ہے کہ اُن کا اعلان اُن سورتوں کے نزول کے وقت ہی نہیں ہوا بلکہ کچھ عرصہ بعد ہوا.پس میور کا مطلب یہ ہے کہ ابتدائی چند سورتوں کے بعد یہ نازل ہوئی.سورۃ عبس کا پہلی سورۃ سے تعلق اس سورۃ کا پہلی سورۃ کے ساتھ ایک تو قریبی تعلق ہے اور ایک سارے مضمون کے لحاظ سے.قریبی تعلق تو یہ ہے کہ پچھلی سورۃ کی آخری آیت سے پہلی آیت میں یہ مضمون تھا کہ اِنَّمَاۤ اَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَّخْشٰىهَا.کہ ڈرانا اسی کو مفید ہو سکتا ہے جو یَوْمُ الْحِسَاب یا انجامِ اعمال سے ڈرتا ہو.یَخْشٰھَا کی ضمیر سَاعَۃٌ کی طرف جاتی ہے اور ہم سَاعَۃٌ کے دونوں معنے کرتے ہیں.حیات بعد الموت بھی اور غلبہ اسلام یا غلبہ قرآن بھی.پس اس میں ان دونوں باتوں کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے کہ اِنَّمَاۤ اَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَّخْشٰىهَا.(النازعات:۴۶) جو شخص حیات بعد الموت سے خوف رکھتا ہو یا اپنے اعمال کےانجام سے ڈرتا ہو کہ جو اعمال میں کر رہا ہوں اُن کے نتیجہ میں تو اسلام جیتتا نظر آتا ہے اور میں ہارتا دکھائی دیتا ہوں اُس شخص کو یہ انذار مفید ہو سکتا ہے چنانچہ اسی لحاظ سے اب اس سورۃ میں ذکر فرماتا ہے کہ اُن لوگوں کی طرف زیادہ توجہ کرو جو حق کو غور سے سُننے کے شائق ہیں اور حق کی قبولیت کا استحقاق اپنے اندر رکھتے ہیں.حق کی قبولیت کا ستحقاق کئی طرح سے ہوتا ہے.اوّلؔ اعمال سے یعنی ایک شخص کے اندر جہاں تک اُس کا ایمان ہے خشیۃ اللہ پائی جاتی ہے یا سنجیدگی پائی جاتی ہے اور وہ دین کی باتوں کو غور سے سُنتا ہے اور یا پھر قومی استحقاق اس طرح ہوتا ہے کہ جب بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے انبیاء آتے ہیں بالعموم ادنیٰ اور غریب طبقہ کے لوگ اُن کی طرف آتے ہیں گویا انبیاء کی بعثت پر
Page 220
نوّے فی صد ی احتمال یہ ہو گا کہ غرباء جلدی دین کو سیکھیں گے.اگر کسی نبی کی جماعت زیادہ تر امراء کی طرف توجہ رکھے گی تو وہ اپنے دائرہ ترقی کو محدود کر دے گی.بے شک امراء بھی آتے ہیں مگر نسبت سے کم.اس فرق کو بھی قرآن کریم نے کئی جگہ بیان فرمایا ہے.مضمون کے لحاظ سے اس کا پہلی سورۃ سے یہ تعلق ہے کہ پہلی سورۃ میںاور اس سے بھی پہلی سورۃ میںیہ بیان کیا گیا تھا کہ خدا تعالیٰ نے اسلام کی ترقی مقدر کی ہے اور اس کے ذرائع بھی بتائے گئے تھے جو یہ تھے.وَ النّٰزِعٰتِ غَرْقًا.وَّ النّٰشِطٰتِ نَشْطًا.وَّ السّٰبِحٰتِ سَبْحًا.فَالسّٰبِقٰتِ سَبْقًا.فَالْمُدَبِّرٰتِ۠ اَمْرًا.اب یہ بتاتا ہے کہ جس طرح ساعت کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے کہ وہ کب ظاہر ہو گی.اسی طرح اس بات کا علم بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے کہ وہ کن لوگوںکے ہاتھ سے ظاہر ہو گی اور وہ نَازِعَات اور نَاشِطَات اور سَابِحَاتِ اور سَابِقَات اور مَدَبِّرَات بننےوالے کون ہوں گے مطلب یہ کہ وہ لوگ جو قوم میں بظاہر بڑے نظر آتے ہیں بظاہر بڑے ہوشیار اور کام کرنے والے دکھائی دیتے ہیں.ہماری یہ مراد نہیں کہ تمہیں وہ لوگ مل جائیں گے کیونکہ ہو سکتا تھا کہ یہ خیال کر لیا جاتا کہ النَّازِعَات سے فلاں فلاں آدمی مراد ہیں یا فلاں فلاں کام کرنے والے مراد ہیںیا فلاں فلاں بڑے آدمی مراد ہیں اور اس طرح قیاس کر لیا جاتا کہ یہ یہ شخص اس سے مراد ہوں گے.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسا نہیں ہے جس طرح خدا تعالیٰ نے ساعت کا علم اپنے پاس رکھا ہوا ہے اسی طرح نَازِعَات بننے والی روحیں اور نَاشِطَات اور سَابِحَات اور سَابِقَات اور مُدَبِّرَات بننے والی روحیں بھی خدا تعالیٰ کے علم میں ہی ہیں تم اُن کے متعلق کوئی قیاس نہیں کر سکتے.تم ظاہر میں سمجھو گے کہ فلاں فلاں شخص قابل ہیں لیکن درحقیقت وہ اندرونی طور پر قابل نہیں ہوں گے.یہ علم بھی سَاعَۃ کی طرح خدا تعالیٰ نے اپنے پاس ہی رکھا ہوا ہے گویا اَلنَّازِعَات کے مستحق لوگ خدا تعالیٰ کے علم میں ہیں وقت پر وہ اُن کو لاتا جائے گا خود اُن کی جستجو کرنا مفید نہیں ہو سکتا.خدا تعالیٰ کی سُنّت ہے کہ وہ اپنے سلسلہ کو اُن لوگوں کی معرفت ترقی نہیں دیتا جو پہلے سے جانے بوجھے ہوتے ہیں بلکہ اُن کے ذریعہ سے ترقی دیتا ہے جو کلّی طور پر اُس دین سے عزت پاتے ہیں جن کی نسبت یہ کہا جائے کہ دین نے اُن سے عزت پائی وہ سچے دین کے قابل نہیں.سچے دین کے قابل وہی ہوتا ہے جس کے متعلق کہا جائے کہ دین سے اُس نے عزت پائی.نبی کے زمانہ میں اُس کے اَتباع خدا تعالیٰ کی طرف اشارہ نہیں کرتے کہ اے لوگو! اُس کو مان لو.بلکہ خدا تعالیٰ ان لوگوں کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ لوگو یہ وہ ہیں جن کو میں خدمت دین کے لئے چُنتا ہوں.پس اس سورۃ میں اَلنَّازِعَات کی جماعت کی تشریح کی گئی ہے اور اُن کے انتخاب کا طریق بتایا گیا ہے جو یہ ہے کہ وقت پر اللہ تعالیٰ اُن
Page 221
کو خود ظاہر کرے گا.چنانچہ اسلام کی تاریخ کو دیکھ لو جتنے لوگ چُنے گئے وہ وہی ہیں جن کی صداقت اور نیکی کا دشمن معترف تھا.لیکن اس زمانہ کے ماحول کے مطابق اگر دنیا کو کہا جاتا کہ اس کام کے لئے آدمیوں کو چنو تو وہ کبھی اُن کو نہ چنتی.کیونکہ گو اُن کے اندر مخفی قابلیتیں تھیں لیکن ایک مبہم خیال سے زیادہ لوگ ان کی اہمیت کو نہیں سمجھتے.آخر مکّہ والے ابو بکرؓ کی قابلیت کے تو قائل تھے مگر سرداری کے لئے توانہوں نے ابو جہل،عتبہ اور شیبہ کو ہی چنا ہوا تھا.کیونکہ ابو بکرؓ کے اندر وہ ایک مبہم نیکی پاتے تھے.ظاہری قابلیتیں ان کو عتبہ، شیبہ اور ابو جہل میں ہی نظر آتی تھیں.اسی طرح عمرؓ، عثمانؓ، علیؓ، عبداللہ بن مسعودؓ، زیبرؓ اور طلحہؓ وغیر ہم میں سے ایک بھی نہیں تھا جس کو قوم نے اپنی سرداری کے لئے منتخب کیا ہو.اسی طرح یمن میں مثلاً ابوموسیٰ اشعری ایمان لائے اور یہود میں سےعبداللہ بن سلام ایمان لائے.مگر کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ اگر اُن کی قومیں منتخب کرتیں تو وہ انہی لوگوں کو کرتیں.یقیناً وہ دوسروں کو کرتیں لیکن اِس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ایک مبہم اقرار اُن کی نیکی کا لوگوں کے دلوں میںضرور موجود تھا.غرض یہ لوگ ایسے تھے کہ قوم میں کسی تغیر کا پیدا کرنا ان سے متوقع نہیں ہو سکتا تھا.مگر تغیر پیدا انہوں نے ہی کیا اور جن سے تغیر متوقع ہو سکتا تھا وہ محروم رہ گئے.پس یہ ایک نہایت ہی اہم معاملہ قومی ترقی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور اس مضمون پر اس سورۃ میں خاص طور پر بحث کی گئی ہے کہ جب قوموں پر تغیر کا زمانہ آتا ہے تو اصل قابلیتیں دب جاتی ہیں اور جھوٹی قابلیتیں ابھرآتی ہیں لوگوں کے مزاج کچھ ایسے بگڑ جاتے ہیں کہ حقیقی نیکی کو وہ پسند نہیں کرتے اور مظاہرے اور بناوٹ اور قوم کی رگ پہچاننے کو وہ زیادہ قدر کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں وہ اس شخص کو آگے نہیں آنے دیتے جو حقیقی لیڈر ہو.بلکہ اُسے آگے لاتے ہیں جو نام کا تو لیڈر ہو لیکن واقعہ میں قومی رسوم اور عادات کے پیچھے چلنے والا ہو اس لئے زمانۂ ظلمت کی اصلاح کے لیڈر کا چننا لوگوں کے لئے ناممکن ہوتا ہے کیونکہ ان کی فطرتیں مسخ اور غلامانہ بن چکی ہوتی ہیں جو اس نیک جدّت کو بھی جو رسم ورواج کے خلاف ہو قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتیں پس اس انتخاب کا حق اللہ تعالیٰ اپنے قبضہ میں رکھتا ہے کیونکہ خدا کی نظر دلوں پر ہوتی ہے صرف منہ کی باتیں وہ پسند نہیں کرتا.ایک عام انسان تو کہہ سکتا ہے کہ اگر یہ لوگ لائق ہیں تو آگے کیوں نہیں آگئےلیکن خدا جانتا ہے کہ اُن کا آگے نہ آنا حالات کے ناسازگار ہونے کی وجہ سے ہے.قوم کے حالات ہی گندے ہو جاتے ہیں اور اس گندی زمین میں کوئی پاکیزہ درخت اُگ ہی نہیں سکتا اور جب تک اس زمین میںسے اُن کو نہ اکھاڑا جائے وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتے.اسی کی طرف سورۂ نازعات میں اشارہ کیا گیا ہے کہ قابل تو یہ ہیں مگر زمین خراب ہے اس زمین میں یہ اُگ نہیں سکتے.اب ہم ایک نئی زمین ان لوگوں کے لئے پیدا کریں گے تب اُن کی قابلیتیں تمہیں نظر آنے لگ جائیں گی.چنانچہ ہم
Page 222
دیکھتے ہیں رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکرؓ خلیفہ ہوئے.جب مکّہ میں یہ خبر اُس جگہ پہنچی جہاں اُن کے والد بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے مدینہ سے آنے والے ایک آدمی سے پوچھا کہ سنائو مدینہ کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں انہوں نے پوچھا تو پھر مسلمانوں کا کیا حال ہے؟اُس نے جواب دیا کہ انہوں نے ایک آدمی کی بیعت کر لی ہے.انہوں نے کہا کس آدمی کی؟ وہ کہنے لگا ابوبکرؓ کی.انہوں نے حیرت سے پوچھا کون ابوبکرؓ؟ اُس نے جواب دیا ابن ابی قحافہ.کہنے لگے کون ابو قحافہ؟ اُس نے کہا تم.پھر انہوں نے مختلف خاندانوں کے نام لے کر پوچھا کہ کیا انہوں نے بیعت کر لی ہے؟جب اُس نے بتایا کہ انہوںنے بیعت کر لی ہے تو وہ کہنے لگے بنو ہاشم کا کیا حال ہے.کیا انہوں نے بھی بیعت کر لی؟ اُس نے کہا ہاں.پھر انہوں نے بعض اور قبائل کے متعلق پوچھا اُس نے یہی جواب دیا کہ اُنہوں نے بھی بیعت کر لی ہے.ابو قحافہ ظاہر میں تو اسلا م لے آئے تھے لیکن ابھی پورے طور پر اُن کے دل میں ایمان داخل نہیں ہوا تھا جب انہوں نے یہ باتیں سُنیں تو تھوڑی دیر تک خاموش سر جھکائے بیٹھے رہے.اس کے بعد انہوں نے اپنا سر اٹھایا اور کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ محمدؐ اللہ کے رسول ہیں(طبقات الکبریٰ لابن سعد جلد سوم صفحہ ۱۸۴ زیر عنوان ذکر بیعۃ ابی بکر).گویا یہ دن اُن کے ایمان کی صفائی کا تھا جس میں اُن کو اسلام کی سچائی کے متعلق حقیقی بصیرت حاصل ہوئی.اُن کے ذہن میں یہ کبھی خیال بھی نہیں آیا تھا کہ کوئی دن ایسا بھی آسکتا ہے جب ابوبکرؓ کو عرب کے سارے قبائل اپنا خلیفہ اور بادشاہ مان لیں گے اور یہ بات بھی ٹھیک ہے جس ابو بکرؓ کو انہوں نے پالا تھا اور جس نگاہ سے انہوں نے ابو بکر ؓ کو دیکھا تھا وہ ابو بکر واقعہ میں اُس وقت اس عظیم الشان منصب کے قابل نہیں تھا.مگر اُس کی وجہ یہی تھی کہ اُنہیں اس مٹی میں اُگایا جا رہا تھا جس سے اُن کو کوئی مناسبت نہ تھی.جب خدا نے زمین بدل دی اور وہ زمین اس پودے کے مناسب حال ہو گئی تب ابوبکرؓ کی روح کا پودا ابھرااور اُس نے نشوونما پاتے پاتے ایک بہت بڑے درخت کا رنگ اختیار کر لیا.یہ بالکل ویسی ہی بات ہے جیسے آم کشمیر میںلگادو تو وہ نہیں اُگیں گے.اور اگر سیب کا درخت پنجاب میں بو دو تو وہ کبھی اچھا پھل نہیں دے گا.نیک روحوں کے لئے بھی مناسب حال زمین کی ضرورت ہوتی ہےاور زمین کے لئے مناسب حال پودے کی ضرورت ہوتی ہے.کفر کی زمین میں عتبہؔ شیبہؔاور ابوجہلؔ ہی بڑھ سکتے تھے.ابو بکر سر نہیں اٹھا سکتے تھے اور ایمان کی زمین میں ابو بکر ؓہی بڑھ سکتے تھے.عتبہ ،شیبہ اور ابوجہل سر نہیں اٹھا سکتے تھے.وہ اس زمین میں جھاڑیوں سے بھی زیادہ ذلیل نظر آتے تھے بلکہ جھاڑیاں تو کیا اُن کی گھاس پُھونس جیسی حیثیت بھی نہیں تھی.اسی مضمون کی طرف اس سورۃ میں اشارہ کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ تم کو وہ روحیں نظر نہیں آتیں جنہوں نے دین کی اشاعت کا کام
Page 223
سرانجام دینا ہے اور جن کے ہاتھوں پر اسلام کا غلبہ مقدر ہے.اِسی لئے تم پوچھتے ہو کہ وہ روحیں آئیں گی کہاں سے جو نَازِعَات.نَاشِطَات.سَابِقَات.سَابِحَات اور مُدَبِّرَات ہوں گی اوران روحوں کو چُنے گا کون؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم چُنیں گے اور کون چُنے گا.بے شک آج وہ روحیں تم کو نظر نہیں آتیں مگر اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہاری زمین ناسازگار ہے.تمہارے باغ میں وہ نیکی کے پودے تو لگے ہوئے ہیں مگر زمین کے مناسب حال نہ ہونے کی وجہ سے وہ سُوکھ رہے ہیں.جب ہم ان پودوں کو اس زمین سے اکھیڑ کر اصل زمین میں بوئیں گے تو اُس وقت تم دیکھو گے کہ وہ کیسےشاندار درخت بنتے ہیں.بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۰۰۱ (میں) اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا بار بار رحم کرنے والا ہے (پڑھتا ہوں) عَبَسَ وَ تَوَلّٰۤىۙ۰۰۲اَنْ جَآءَهُ الْاَعْمٰىؕ۰۰۳ (کیا) چیں بجبیں ہو گیا اور مُنہ موڑ لیا؟ (صرف) اس بات پر کہ اُس کے پاس (ایک) نابینا (جسے واقف لوگ جانتے ہیں) آیا؟ حَلّ لُغَات.عَبَسَ عَبَسَ فُلَاَنٌ وَجْھَہٗ کے معنے ہوتے ہیں قطَّبَہٗ.اُس نے ناراضگی کا اظہار کرنے کے لئے ماتھے پر شکن ڈال لئے (اقرب) اور تَوَلَّی عَنْہُ کے معنے ہوتے ہیں اَعْرَضَ عَنْہُ وَتَرَکَہٗ.اس سے اعراض کرلیا اور اُس سے توجہ کو ہٹا لیا.(اقرب) تفسیر.سورۃ عبس کا شانِ نزول کہا جاتا ہے کہ عبداللہ بن اُم مکتوم ایک دفعہ رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف لائے.یہ اس وقت تک مسلمان ہو چکے تھے یا اگر ظاہری طور پر انہوں نے بیعت نہ کی ہو تو بہرحال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے تھے.جب یہ رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے تو اُس وقت آپ کے پاس عتبہ و شیبہ (ربیعہ کے دونوں بیٹے جو مکّہ کے لیڈروں میں سے تھے) اور ابو جہل اور عباس ابن عبدالمطلب اور امیہ بن خلف اور ولید بن مغیرہ بیٹھے ہوئے تھے اَور آپ ان کو بڑے شوق سے تبلیغ کر رہے تھے کہ شاید یہ مان جائیں تو اُن کے ذریعہ سے باقی مکّہ والے بھی اسلام میں داخل ہو جائیں باتیں ہو ہی ر ہی تھیں کہ عبداللہ بن ام مکتوم آئے اور انہوں نے رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ
Page 224
اَقْرِئْنِیْ وَعَلِّمْنِیْ مِمَّا عَلَّمَکَ اللّٰہُ تَعَالٰی کہ مجھے قرآن پڑھائیے اور جو کچھ خدا تعالیٰ نے آپ کو سکھایا ہے وہ مجھے بھی سکھائیے رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم نے اُن کی بات کا کوئی جواب نہ دیا.جس پر انہوں نے دو تین بار اسی بات کو دُہرایا چنانچہ لکھا ہے وَلَمْ یَعْلَمْ تَشَاغُلَہٗ بِالْقَوْمِ یعنی اُن کو علم نہ ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں سے باتیں کر رہے ہیں.فَکَرِہَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم قَطْعَہُ لِکَلَامِہٖ وَ عَبَسَ وَاَعْرَضَ عَنْہُ رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم نے اُن کے قطع کلام کو ناپسند فرمایا اور آپ کے ماتھے پر شکن پڑے اور آپ نے اُن سے اعراض کر لیا.اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ توبیخ نازل ہوئی (کشاف زیر آیت ھذا) چنانچہ رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم نے بعد میں اُن کو بلا کر اُن کی عزت افزائی کی اور اُن سے باتیں کیں اور اس کے بعد جب کبھی وہ آپ کے پاس آتے آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم اُن کے لئے چادر بچھادیتے اور انہیں اس پر بیٹھنے کے لئے کہتے.(فتح البیان زیر آیت ھذا) یہ واقعہ ہے جو اس سورۃ کا شانِ نزول بتا یا جاتا ہے اور وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم نے ایک اندھے کو حقیر جانا اور یہ سمجھ کر کہ وہ معمولی اور غریب آدمی ہے اس کی طرف کوئی توجہ نہ کی.اور وہ بڑے بڑے خاندانوں کے لوگ جو اس وقت آپ کے پاس موجود تھے اُن کی طرف ہی آپ نے اپنی توجہ رکھی اور یہ سمجھا کہ مشہور خاندانی لوگوں کی طرف توجہ رکھنا زیادہ مفید ہو سکتا ہے ایک اندھے اور غریب کی طرف توجہ کی کیا ضرورت ہے.اس روایت کے سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ سب سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ عبداللہ بن ام مکتوم کون تھا.عبداللہ بن ام مکتوم حضرت خدیجہؓ کے بھائی تھے یعنی اُن کے ماموں کے بیٹے تھے اُن کے نام اور نسب کے متعلق قریب کے ناموں میں اختلاف ہے مگر قوم کے لحاظ سے سب اس بات پر متفق ہیں کہ بنی عامر بن لُؤَیِّ میں سے تھے.اُن کا نام اور نسب نامہ بعض عبداللہ بن شریح بن مالک بن ربیعۃ الفہری بتاتے ہیں اور بعض عبداللہ بن عمرو بن قیس ابن زائدہ بن الاعصم بتاتے ہیںاور بعض اُن کا نام ہی عمرو بن قیس ابن زائدہ بتاتے ہیں (روح المعانی زیر آیت ھذا) یہ ابن ام مکتوم کیوں کہلاتے ہیں اس کے متعلق زمخشری نے لکھا ہے کہ اُم مکتوم اُن کی دادی کا نام تھا(تفسیر کشاف زیر آیت ھذا).لیکن ابن عبدالبرّ اور دوسرے مؤرخین کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے اُن کے نزدیک یہ اُن کی والدہ کی کنیت ہے اور ان کا اصل نام عاتکہ بنت عامر بن مخزوم تھا(الاصابۃ فی تمییز الصحابۃ حرف العین).اُن کی کنیت ام مکتوم اس لئے تھی کہ یہ پیدا ہی اندھے ہوئے تھے اس لئے ان کی کنیت ام مکتوم پڑ گئی یعنی اندھے کی ماں.بعض مؤرخین یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ اندھے پیدا نہیں ہوئے تھے کچھ دیر تک اُن کی آنکھیں سلامت رہیں مگر بعد میں کسی
Page 225
وجہ سے اُن کی بینائی جاتی رہی.رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم نے دو دفعہ اُن کو مدینہ کا امیر بھی مقرر فرمایا.(استیعاب فی معرفۃ الاصحاب جلد ۳ صفحہ ۲۷۶ زیر عنوان عمرو بن قیس بن الاعصم) اس شجرۂ نصب کو تفصیل کے ساتھ بیان کرنے سے میری غرض یہ ہے کہ یہ کہنا کہ وہ حقیر آدمی تھے اور اُن کی طرف رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم کی توجہ مفید نہیں ہو سکتی تھی ان واقعات سے بالبداہت غلط ثابت ہوتا ہے اس لئے کہ ان کی والدہ اور والد دونوں زبردست قبائل میں سے ہیں.اور یہ ایک ایسی عورت کے بھائی ہیں جس کی رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم کے دل میں انتہاء درجہ کی عزّت تھی اور اس حد تک عزت تھی کہ اُن کی وفات کے سالوں بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہاکو اُن پر رشک آجاتا تھا.حضرت عائشہ ؓ خود بیان کرتی ہیں کہ جب رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم تکرار اور تواتر کے ساتھ حضرت خدیجہؓ کا ذکر فرماتے تو میں بعض دفعہ بے تاب ہو کر کہتی یا رسول اللہ! آپ اُس بڑھیا کا ذکر چھوڑ یں گے بھی یا نہیں.اللہ تعالیٰ نے توآپ کو اس سے بہت بہتر عورتیں دے دی ہیں؟ اُس وقت رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم اُن کے جواب میں فرماتے عائشہ! تم کو معلوم نہیں خدیجہؓ کے اندر کتنی خوبیاں تھیں اور اس نے میری ایک لمبے عرصہ تک کیسے خدمت کی.پس حضرت خدیجہؓ کے بھائی اور ماں اورباپ دونوں کی طرف سے زبردست خاندانوں کے فرد کی عظمت صرف نابینا ہونے کی وجہ سے تو نہیں جا سکتی تھی.آخر تبلیغ زبان سے کی جاتی ہے آنکھوں سے تو نہیں کی جاتی.پس یہ کہنا کہ رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھا کہ ایک حقیر اندھا آدمی میرے پاس آیا ہے میں بڑے بڑے لوگوں کو چھوڑ کر ایسے غریب اور معمولی آدمی کی طرف کیوں توجہ کروں بالبداہت واقعات سے غلط ثابت ہوتا ہے.پھر رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم نے اُن کو دو دفعہ مدینہ کا سردار مقرر کیا اور یہ سردار مقرر کرنا محض لحاظ کے طور پرنہیں ہو سکتا تھا بلکہ اگر رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم نے اُن کو سردار مقرر فرمایا تو اس لئے کہ ان میں امارت کی قابلیت تھی اور اس لئے رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم یہ سمجھتے تھے کہ عرب ان کی خاندانی عظمت کی وجہ سے انہیں اپنا سردار تسلیم کرنے میں کوئی تکلیف محسوس نہیں کریں گے.کیونکہ عرب کے دستور کے مطابق کوئی ایسا شخص امیر مقرر نہیں کیا جا سکتا تھاجس کا خاندانی لحاظ سے لوگوں پر اثر نہ ہوتا.اسی وجہ سے رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم نے جب بھی امیر مقرر کیا ہمیشہ انہی لوگوں کو کیا جو خاندانی لحاظ سے عظمت وشہرت کے مالک ہوتے تھے اور جن کے متعلق یہ توقع کی جا سکتی تھی کہ لوگوں کو اُن کی اطاعت سے کوئی گریز نہیں ہوگا.چنانچہ ایک دفعہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بعد امیر مقرر فرمایا(السیرۃ النبویۃ لابن ہشام زیر عنوان غزوۃ تبوک).حقیقت یہ ہے کہ عربوں میں نسلی تعصب اس قدر بڑھا ہوا تھا کہ وہ ادنیٰ اقوام یا بے اثر لوگوں کی امارت کو تسلیم ہی نہیں کر سکتے تھے.یہ تو بہت لمبے عرصہ کے بعد
Page 226
اسلام نے ان کے دلوں سے یہ بات دُور کی ورنہ شروع شروع میں یہ بالکل ناممکن تھا کہ وہ کسی ایسے آدمی کی امارت کو قبول کرنے کے لئے تیار ہو جاتے جو خاندانی طور پر کوئی اثر نہ رکھتا ہو.پس یہ سمجھنا کہ رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک حقیر آدمی آیا اور آپ نے اُس کی طرف محض اُس کی غربت اور عدم عزّت کی وجہ سے توجہ نہ کی بالبداہت باطل ہے اور یہ اتنا موٹا مضمون ہے کہ تعجب آتا ہے مسلمانوں کی سمجھ میں کیوں نہیں آیا حالانکہ بعض دشمنانِ اسلام کی سمجھ میں آگیا ہے چنانچہ نولڈکے NOLDEKEجو مشہور جرمن مستشرق ہے وہ یہ واقعہ لکھ کر کہتا ہے کہ یہ بالکل جھوٹا واقعہ ہے عبداللہ بن ام مکتوم کا شجرہ نصب بتا رہا ہے کہ وہ کوئی معمولی آدمی نہیں تھا(Wherry Commentery on Quran vol 4 pg.218).اور اس لئے یہ بات اس کے متعلق ہر گز نہیں ہو سکتی گویا اُس کا ذہن بھی اِدھر چلا گیا کہ یہ واقعہ یہاں چسپاں نہیں ہوتا.حالانکہ اگر یہ بات درست ہوتی تو اُس کو خوش ہونا چاہیے تھا کہ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس سے محمد رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کی ہتک ہوتی ہے مگر وہ کہتا ہے یہ بات واقعات کے بالکل خلاف ہے اور اسے ان آیات پر چسپاں نہیں کیا جا سکتا.اس سورۃ کے نزول کے متعلق مفسرین کے بیان کئے ہوئے واقعہ پر چسپاں نہ ہونے پر پانچ دلائل میرے نزدیک علاوہ اس شہادت کے پانچ اور امور ایسے ہیں جن کی وجہ سے ہر شخص کو ماننا پڑتا ہے کہ یہ واقعہ اس رنگ میں یہاں چسپاں نہیں ہوتا.پہلی دلیل (۱) پہلی وجہ یہ ہے کہ ابن ام مکتوم اندھے تھے بہرے نہیںتھے.یا تو یہ کہا جاتا کہ ابن ام مکتوم بہرے تھے اور چونکہ بہرے ہونے کی وجہ سے وہ باتوں کو نہیںسُن سکتے تھے اس لئے اُن کو پتہ نہیں لگا کہ رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم بعض دوسرےلوگوں سے مصروف گفتگو ہیں اور چونکہ اُن کو اپنے بہرے پن کی وجہ سے اس بات کا علم نہیں ہو سکا اس لئے انہوں نے آتے ہی سوال کر دیا.اگر یہ ثابت ہو جائے تو پھر ابن ام مکتوم پر کوئی الزام عائد نہیں ہوتا.کیونکہ عدمِ علم کی حالت میں کسی بات کا انسان سے سرزد ہو جانا اُسے موردِ الزام قرار نہیں دے سکتا لیکن تاریخ سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ وہ بہرے تھے.چنانچہ بعض مفسرین کو بھی یہ اعتراض سوجھا ہے کہ جب ہم اس واقعہ کو بیان کر رہے ہیں تو ہر شخص یہ کہے گا کہ قصور ابن ام مکتوم کا ہے جب رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم بات کر رہے تھے تو انہوں نے بیچ میں دخل کیوں دے دیا.آخر ہر شخص جانتا ہے کہ جب دوسرے سے گفتگو کی جا رہی ہو تو اُس وقت اگر کوئی شخص دخل دے دے اور کلام کو قطع کرنے کی کوشش کرے تو وہ تہذیب اور شائستگی کے خلاف حرکت کا مرتکب سمجھا جاتا ہے اور اُسے کسی صورت میں بھی اپنے فعل میں حق بجانب نہیں سمجھا جا سکتا پس جب رسول کریم
Page 227
صلے اللہ علیہ وسلم بعض اور لوگوں سے گفتگو کر رہے تھے اور عبدا للہ بن اُم مکتوم نے اس میں دخل دے دیا اور آپ کی بات کو قطع کرنا چاہا تو ایسی صورت میں عبداللہ بن اُم مکتوم ہی زجر کے قابل تھا کہ اُس نے خلافِ تہذیب ایک حرکت کا ارتکاب کیا.بہرحال یہ ایک اعتراض ہے جو مفسرین کو بھی سوجھا ہے اور انہوں نے اس کا جواب دینے کی بھی کوشش کی ہے مگر وہ جواب ایسا کمزور ہے کہ اُسے پڑھ کر حیرت آتی ہے کہ مفسرین نے یہ کیا کہہ دیا چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم شاید ان لوگوں کو کان میں تبلیغ کر رہے تھے جس کی آواز عبداللہ بن ام مکتوم کو نہیں پہنچی(تفسیر ابن کثیر زیر آیت ھذا).مگر یہ بالکل ہنسی کے قابل بات ہے کہ سات آدمی رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں موجود ہوں اور ان سات آدمیوں کو آپ کان میں تبلیغ کر رہے ہوں اور ایسی ہلکی آوا زسے کہ کوئی پاس کا شخص بھی اُس کو سُن نہ سکے دُنیا کی کوئی عقل اس بات کو تسلیم نہیں کر سکتی اور احمق سے احمق انسان بھی اس بات کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہو سکتا کہ سات آدمی رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور اُن سات آدمیوں کو بجائے کھلے طور پر تبلیغ کرنے کے آپ ہر ایک کے کان کے ساتھ اپنا منہ لگا رہے ہوں اور اُسے اسلام کی تبلیغ کر رہے ہوں.بات یہ ہے کہ فطرت خود بولتی ہے کہ سچائی کیا ہے خواہ اس پر کس قدر پردے ڈالنے کی کوشش کی جائے.بہرحال اگر عبداللہ بن اُم مکتوم رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اس وقت بولے جب آ پ دوسروں کو تبلیغ کر رہے تھے تو ملز م ابن ام مکتوم تھے اور اُن کا کوئی حق نہیں تھا کہ وہ اس وقت بولتے.اور اگر انہوں نے سُنا نہیں کہ رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم تبلیغ کر رہے ہیں تو پھر ثابت کرنا چاہیے کہ وہ بہرے تھے لیکن تاریخ یہ تو بتاتی ہے کہ وہ اندھے تھے یہ نہیں بتاتی کہ وہ اس کے ساتھ بہرے بھی تھے.اور جب وہ بہرے نہیں تھے جب وہ رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کوسُن رہے تھے.جب انہیںمعلوم تھا کہ اس وقت مکہ کے بڑے بڑے رئوساء کو تبلیغ کی جا رہی ہے تو وہ بولے کیوں؟ اُن کااس موقعہ پر بولنا بتا رہا ہے کہ قصور ابن مکتوم کا ہی تھا اور یہ بات تو عقل کے بالکل خلاف ہے کہ رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم بات کر رہے ہوں اور ابن مکتوم نے اُس کو سنا ہی نہ ہو.جیسے مفسرین نے ایک بے بنیاد توجیہہ کی ہے بہرحال جرم ابن ام مکتوم کا ثابت ہوتا ہے مگر بتایا یہ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈانٹ رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم کو پڑی.اسی مشکل کی وجہ سے مفسرین نے عجیب قیاس کیا ہے رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم اُن کو کان میں تبلیغ کر رہے تھے حالانکہ یہ تبلیغ کا موقع تھاکسی کی بیوی کا جھگڑا نہیں تھا کہ اس کے متعلق اسے کان میں کچھ کہنے کی ضرورت ہوتی تاکہ دوسرا شخص اُسے سُن نہ لے.خدا اور رسول کی باتیں تھیں.اسلام کی اشاعت کا کام تھا.توحید کی تعلیم تھی.مگر بتایا یہ جاتا ہے کہ رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم بڑی آہستگی سے عتبہ اور شیبہ کے کان کے ساتھ اپنا
Page 228
منہ لگا کر کہہ رہے تھے کہ دیکھو اللہ ایک ہے.اللہ نے ہی سب دنیا کو پیدا کیا ہے.بُتوں میں کچھ نہیں رکھا.انہیں چھوڑ دو اور توحید کا اقرار کرو.دنیا کا کوئی بھی معقول انسان اسے تسلیم نہیں کر سکتا بلکہ جس شخص کے سامنے بھی یہ بات پیش کی جائے وہ ہنس پڑے گا کہ کیسی جاہلانہ بات کہی جا رہی ہے.دوسری دلیل.(۲) دوسرے اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا تو آپ نے عین ثواب کا کا م کیا اُن پر اعتراض کیسا؟ آپ بڑے بڑے رئوساء کو تبلیغ کر رہے تھے.اُن پر اسلام کی حقیقت واضح کر رہے تھے.اُن کو خدا اور اُس کے رسول کی طرف بُلا رہے تھے.ایسی حالت میں جب ایک شخص نے آپ کے کلام کو قطع کرنا چاہا اور موقع اور محل کو نظرانداز کر کے تہذیب وشائستگی کے اصول کے بالکل خلاف ایک بات پیش کر دی تو اُس وقت رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم نے اگراس کی بات کا جواب نہیں دیا تو آپ نے بالکل درست کیا.قرآن کریم کی کوئی آیت ایسی نہیں جو ہمیں اس فعل سے روکتی ہو بلکہ اگر آج بھی ہماری مجلس میں کوئی ایسی حرکت کرے تو باوجود عَبَسَ وَ تَوَلّٰۤى والی آیت کے نازل ہونے کے ہم آج بھی اس سے وہی سلوک کریں گے جو عبداللہ بن ام مکتوم سے رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم نے کیا.میں اگر قرآن کریم کا درس دے رہا ہوں اور کوئی شخص درمیان میں مجھے آکر کہے کہ اس درس کو چھوڑئیے اور میری فلاں بات کا جواب دیجئے.تو کیا میں اُس وقت درس چھوڑ دوں گا اور اس کی بات کی طرف متوجہ ہو جائوں گا.یا اُس سے اعراض کروں گا کہ اُس نے موقع اور محل کو نظر انداز کر کے سلسلہ کلام کو قطع کرنا چاہا؟ ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ ایسے موقع پر اعراض کرنا ہی ضروری ہوتا ہے.ا گر درمیان میں کوئی شخص دخل دے دے تو اس سے بات کا تسلسل ٹوٹ جاتا ہے.طبائع پر جو اثر ہو رہا ہوتا ہے وہ جاتا رہتا ہے.دلیل بھول جاتی ہے اور دخل دینے والے کی بدتہذیبی کا الگ اثر پڑتا ہے.پس ایسی حالت میں ضروری ہوتا ہے کہ اس کی بات کی طرف توجہ نہ کی جائے.کیا کوئی شخص اس بات کو جائز قرار دے سکتا ہے کہ رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ کی ہستی کا ثبوت پیش کر رہے ہوتے اور ابن ام مکتوم کے دخل دینے پر اُسے سورۂ نَازِعَات کا درس دیناشروع کر دیتے اور جب گھنٹہ بھر گزر جاتا تو پھر اُن لوگوں سے کہتے کہ لواب بقیہ آدھی دلیل تم بھی سن لو؟ دنیامیں جاہل سے جاہل اور احمق سے احمق انسان بھی ایسی حرکت نہیں کرتا مگر یہ لوگ محض اس بات کی وجہ سے رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم کو موردِ الزام قرار دیتے ہیں.اور بتاتے ہیں کہ آپ کو تبلیغ چھوڑ کر ابن ام مکتوم کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے تھا اور تہذیب وتمدن کے تمام اصول کو بالائے طاق رکھ دینا چاہیے تھا.گویا یہ لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کو ایک ایسا رنگ دینا چاہتے ہیں جسے دنیا میں کہیں بھی معقول قرار نہیں دیا جاتا.
Page 229
تیسری دلیل.(۳) تیسرے اندھے کی بات کو ناپسند کر کے اُس پر تیوری چڑھانا اور مُنہ پھیر لینا یہ تو رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ درجہ کے اخلا ق کا ثبوت ہے.اس پر تو آپ کی تعریف ہونی چاہیے تھی نہ یہ کہ توبیخ نازل ہوتی.ایک اندھا شخص آتا ہے وہ ایک غیرمعقول بات کرتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ڈانٹتے نہیں تاکہ اُس کا دل میلا نہ ہو صرف اُس کے بار بار دخل دینے کی وجہ سے آپ کے ماتھے پر شکن آجاتے ہیں لیکن پھر بھی آپ کی زبان سے کوئی لفظ نہیں نکلتے آپ چاہتے تھے کہ اُس کا دل نہ دُکھے مگر دُوسری طرف وہ ایک ایسی بات کر رہا تھا جو سراسر غیر معقول تھی.ایسی حالت میں آپ حیران تھے کہ میں کروںکیا؟ ادھر میں بات کو نہیں چھوڑ سکتادوسری طرف اگر اس کو ڈانٹتا ہوں تو اس کا دل میلا ہوتاہے اب میں کروں توکیا کروں.ایسی حالت میں بہترین طریق جو ایک انسان اختیار کر سکتا ہے وہ یہی ہے کہ وہ مُنہ پھیر لے اور اس طرح دونوں باتیں ہو جائیں سلسلہ کلام بھی نہ رُکے اور دوسرے شخص کے دل کو بھی صدمہ نہ پہنچے.چنانچہ رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر شکن پڑے اور آپ نے اُس کی طرف سے منہ پھیر لیا.مُنہ پھیرنے میں حکمت یہ تھی کہ آپؐ چاہتے تھے مجھے غصہ پیدا نہ ہواگر عبداللہ بن اُم مکتوم میرے سامنے ہو گاتو ممکن ہے غصہ کی حالت میں میرے مُنہ سے کوئی بات نکل جائے.چنانچہ آپ نے تیوری چڑھائی جس کو اندھا نہیںدیکھ سکتا تھا اور پھر اُس سے مُنہ پھیر لیا تاکہ اس کے متعلق زیادہ غصہ پیدا نہ ہو اور زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکلے جس سے اُس کے دل کو صدمہ ہو پس آپ کا یہ فعل تو ایسا تھا کہ اس پر عرش سے خدا تعالیٰ کی طرف سے تعریف آنی چاہیے تھی نہ یہ کہ ڈانٹ پڑتی؟ اور کہا جاتا ہے کہ آپ نے اچھا کام نہیں کیا.پھر اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ طریق اختیار نہ کرتے تو مفسّرین کو بتانا چاہیے تھا کہ آپؐ کیا کرتے اور وہ کون سا دوسرا قدم تھا جو آپ تمام اخلاقی پہلوئوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے اٹھا سکتے تھے.مگر وہ کوئی دوسرا طریق نہیں بتا سکے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اُن کے نزدیک بھی یہی طریق تھا جو اس موقعہ پر اختیار کیا جا سکتا تھا.اگر اس واقعہ سے کچھ پتہ چلتا ہے تو وہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیوری چڑھائی اور آپ کو ابن ام مکتوم کی بات بُری لگی لیکن آپ نے اُسے کوئی جواب نہیں دیا.صرف زائد بات یہ کی کہ جب آپ نے دیکھا کہ وہ باز نہیں آتا تو آپ کو یہ خیال پیدا ہوا کہ ایسا نہ ہواُسے اپنے سامنے بیٹھے دیکھ کر غصہ میں میرے منہ سے کوئی بات نکل جائے.آپ نے اس کی طرف سےاپنا منہ پھیر لیا تا کہ نہ وہ نظر آئے اور نہ اس کے متعلق طبیعت میں زیادہ جوش پیدا ہو اور یہ دونوں باتیں ایسی ہیں جو رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم کے نہایت اعلیٰ درجہ کے اخلاق پر دلالت کرتی ہیں.چوتھی دلیل.(۴)چوتھے ابن اُم مکتوم خود ایک بڑے خاندان کے فرد تھے.اس لئے ان کو حقیر سمجھنے کے کوئی معنے
Page 230
ہی نہیں.لیکن اگر فرض بھی کر لو کہ وہ حقیر تھے تو اُن کے متعلق یہ نہیں کہا جا سکتا کہ رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم نے اُن کی غربت کی وجہ سے یا ان کے ادنیٰ ہونے کی وجہ سےان کی طرف کوئی توجہ نہ کی.کیونکہ رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم غرباء کی طرف خاص طور پر توجہ کیا کرتے تھے اور کبھی کسی شخص کو محض اُس کے غریب ہونے یا اس کے ادنیٰ طبقہ سے تعلق رکھنے کی وجہ سے تحقیر کی نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے.چنانچہ ہم دیکھتے ہیں مکّہ کی زندگی میں ہی آپ غلاموں کو تبلیغ کرتے اور بعض دفعہ گھنٹہ گھنٹہ ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹہ اُن کے پاس کھڑے رہتے اور انہیں محبت اور پیار کے ساتھ اسلام کی باتیں پہنچاتے حالانکہ وہ نہایت ادنیٰ طبقہ کے ساتھ تعلق رکھتے تھے.چنانچہ دو عیسائی غلاموں کے متعلق تاریخ میں ذکر آتا ہے کہ وہ نہایت شوق سے انجیل پڑھا کرتے تھے جب رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم نے اُن کے اندر یہ مذہبی جو ش پایا تو آپ بہت خوش ہوئے اور آپ نے سمجھا کہ یہ لوگ اس بات کے مستحق ہیں کہ ان کو خدا تعالیٰ کا پیغام پہنچایا جائے.چنانچہ آپ اُن کے پاس جاتے اور بڑی بڑی دیر تک اُن کے پاس بیٹھے رہتے وہ عیسائی غلام آہن گری کا کام کرتے تھے.وہ لوہا کوٹتے جاتے اور رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم اُن کے پاس کھڑے ہو کر انہیں تبلیغ کرتے رہتے (تفسیر فتح البیان زیر آیت ولقد نعلم انھم یقولون...).پس وہ شخص جو گلیوں میں ادنیٰ ادنیٰ درجہ کے لوگوں کے پاس کھڑا ہو جاتا تھا.جو غلاموں کو کئی کئی گھنٹے تبلیغ کرتا رہتا تھا.جو غریب اور معمولی طبقہ کے لوگوں سے ملنے میں اپنی کوئی ہتک محسوس نہیں کرتا تھا.اُس کے متعلق یہ کس طرح کہا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ایک شخص کی طرف محض اس لئے متوجہ نہ ہوا کہ وہ غریب آدمی تھا.جو شخص غلاموں کے ساتھ برسرِ بازار گفتگو کرنے سے نہیںگھبراتا تھا اور جو شخص اُن کو تبلیغ کرنے میں اپنی کوئی ہتک محسوس نہیں کرتا تھا اُس کے لئے یہ کوئی شرم کی بات نہیں تھی کہ وہ ابن ام مکتوم سے بات کر لیتا بشرطیکہ اخلاق اس بات کی اجازت دیتے.پانچویں دلیل.(۵) پانچواں ردّ اس کا یہ ہے کہ اگر یہ توبیخ تھی اور اگر اس آیت کے ذریعہ رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم کو نعوذباللہ ڈانٹا گیا تھا تو پھر چاہیے تھا کہ آپ اپنے رویّہ کو بدل لیتے کیونکہ ہمیں بتایا یہ جاتا ہے کہ رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم نے اس واقعہ کے بعد ابن ام مکتوم کو بلایا اور اُسے کہا کہ بتائو تم مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو تمہاری خاطر تو خدا نے مجھ کو ڈانٹا ہے.(تفسیر فتح البیان زیر آیت ھذا) پس اگر یہ واقعہ درست ہے تو اس کے بعد لازمی طور پر رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم کو اپنا سابق طریقِ عمل بدل لینا چاہیے تھا اور آئندہ یہ دستورُالعمل بنا لینا چاہیے تھا کہ جب بھی کوئی شخص آپ کی بات میں دخل دیتا آپ فوراً اس کی طرف متوجہ ہو جاتے اور اپنے سلسلۂ کلام کو منقطع کر دیتے.مگر ہمیں تاریخ سے ایسے واقعات نظر آتے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم نے بعد
Page 231
میں بھی اپنا یہی طریق عمل رکھا.چنانچہ بخاری میں آتا ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا حضور اُس وقت مجلس میںگفتگو فرما رہے تھے اُس نے آپ کے کلام میںدخل دیتے ہوئے ایک سوال کیا مگر آپ نے اُس کا جواب نہیں دیا اور اپنی بات میں ہی مشغول رہے یہاں تک کہ صحابہ کہتے ہیں ہم نے سمجھا کہ رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم شاید خفا ہو گئے ہیں.جب آپ بات ختم کر چکے تو آپ نے فرمایا کہ سائل کہاں ہے؟ اور پھر آپ نے اُس کے سوال کا جواب دیا (بخاری کتاب العلم باب منْ سُئِلَ عِلْمًا وَھُوْ مُشْتَغِلاً فِی حَدِیْثِہٖ فاتّم الحدیث ثم اجاب السائل) گویا وہ طریق جو ابن ام مکتوم کے واقعہ کے وقت آپ نے اختیار کیا تھا وہی طریق آپ نےبعد میں بھی جاری رکھا اور جب بھی کسی شخص نے آپ کی گفتگو کے دوران میں دخل دے کر آپ سے کوئی سوال کرنا چاہا آپ نے کبھی اس کا جواب نہیں دیا جب تک اپنی بات کوختم نہیں کر لیا.اور یہ طریق وہ ہے جو نہ صرف مکّہ مکرمہ میں بلکہ مدینہ منورہ میں بھی آپ نے جاری رکھا.بلکہ جیسا کہ دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے آپ کا عام طریق ہی یہ تھا کہ جب تک بات ختم نہ کر لیتے کسی دوسرے شخص کے سوال کا جواب نہ دیتے اور یہی شرفاء کا طریق ہے.پس اگر واقعہ میں یہ توبیخ ہوتی تو پھر چاہیے تھا کہ اِن آیات کے نزول کے بعد رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی شخص بات کرتا اور جس حالت میں بھی کرتا آپ فوراً اس کا جواب دینا شروع کر دیتے اور سمجھتے کہ میں اُس غلطی کا اعادہ نہ کروں جو ایک دفعہ مجھ سے ہو چکی ہے.لیکن آپ نے کبھی اپنے طریق کو نہیں بدلا.اور جب آپ نے وہی رویّہ رکھا جو ابن اُم مکتوم کے واقعہ کے وقت تھا تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ توبیخ کس بات پر تھی اور کس بات سے رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم کو روکا گیا تھا؟ رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم کا عمل تو ثابت کررہا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کے آخر تک عَبَسَ وَ تَوَلّٰۤى والی بات پر ہی عمل کیا اور جب بھی کوئی شخص آپ کی بات میں دخل دیتا آپ اُسے پسند نہ فرماتے.کیونکہ تداخل سے تسلسل ٹوٹ جاتا ہے.اثر جاتا رہتا ہے.بات پوری نہیں ہوتی اور مضمون کے کئی پہلو ذہن سے نکل جاتے ہیں.پس اگر اس واقعہ کو درست تسلیم کیا جائے تو اس کے معنے یہ ہوں گے کہ رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ڈانٹ بھی پڑی مگر آپ پھر بھی نہ مانے.میں اِن دلائل کے بیان کرنے سے پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ عبداللہ بن ام مکتوم کے حالات بتاتے ہیں کہ وہ کوئی ذلیل یا حقیر آدمی نہیں تھے.بیشک وہ اندھے تھے لیکن آخر وہ رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے تھے حضرت خدیجہؓ کے ماموں زاد بھائی تھے اور باپ اور ماں کی طرف سے بھی مشہور خاندانوں میں سے تھے.اس خاندانی اثر کیو جہ سے اور رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہؓ کے تعلقات
Page 232
کی وجہ سے اُنہیں آپ کا مقرب ہونا چاہیے تھا اور جیسا کہ واقعات ثابت کرتے ہیں وہ آپ کے مقرب ہی تھے.چنانچہ بعد میں رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم کا انہیں دو دفعہ اپنے بعد مدینہ کا امیر مقررکرنا اسی بات کا ثبوت ہے کہ رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم کے دل میں ان کا احترام پایا جاتا تھا اور آپ اُن کے خاندانی اثر کے قائل تھے.پس یہ دلیل بھی اس واقعہ کے غلط ہونے کا ایک بیّن ثبوت ہے.سورۃ کی پہلی آیات میں مفسرین کو پیش آنے والی مشکلات کا حل میرے نزدیک ان آیات میں ہی خدا تعالیٰ نے ایک حل رکھ دیا ہے جس کی طرف مفسّرین نے توجہ نہیں کی.اُن کا ذہن ادھر گیا ہے مگر وہ اس کی اَوراور توجیہیں کرتے رہے ہیں.اور وہ حل یہ ہے کہ ان آیات کی بناوٹ اور ان کی ترتیب پر ہمیں غور کرنا چاہیے.یہ آیات اس طرح ہیں عَبَسَ وَ تَوَلّٰۤى.اَنْ جَآءَهُ الْاَعْمٰى.وَ مَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّهٗ يَزَّكّٰۤى.اَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرٰى.اَمَّا مَنِ اسْتَغْنٰى.فَاَنْتَ لَهٗ تَصَدّٰى.وَ مَا عَلَيْكَ اَلَّا يَزَّكّٰى.وَ اَمَّا مَنْ جَآءَكَ يَسْعٰى.وَ هُوَ يَخْشٰى.فَاَنْتَ عَنْهُ تَلَهّٰى.اِن آیات میں عَبَسَ وَ تَوَلّٰۤى.اَنْ جَآءَهُ الْاَعْمٰى.تین غائب کے صیغے ہیں.یعنی کسی نے عَبُوْس اختیار کیا.کسی نے تَوَلّٰٓی کی اور کسی کے پاس اَعْمٰی آیا.لیکن آگے فرماتا ہےوَ مَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّهٗ يَزَّكّٰۤى تجھ کو کس نے بتایا کہ اس کے متعلق یہ امید کی جا سکتی تھی کہ وہ تزکیہ حاصل کر لے گا.یہاں غائب کی بجائے مخاطب کا صیغہ آگیا.اسی طرح اَمَّا مَنِ اسْتَغْنٰى.فَاَنْتَ لَهٗ تَصَدّٰى.میں مخاطب کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے گویا یہاں کچھ غائب کے صیغے ہیں اور کچھ مخاطب کے صیغے ہیں ان غائب اور مخاطب کے صیغوں کے متعلق چار ہی صورتیں ہیں.(۱) یا تو ہم غائب اور مخاطب دونوں کو رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم کے متعلق سمجھیں.(۲) یا ہم غائب اور مخاطب دونوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غیر کے متعلق سمجھیں یعنی یا تو ہم یہ سمجھیں کہ عَبَسَ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے اور مَایُدْرِیْکَ بھی رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے اور یا ہم یہ سمجھیں کہ عَبَسَ بھی رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کے متعلق ہے اور مَایُدْرِیْکَ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کے متعلق ہے (۳) اور یا پھر ہم یہ سمجھیں کہ عَبَسَ رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے اور مَا یُدْرِیْکَکسی اور کے متعلق ہے (۴)اور یا پھر ہم یہ سمجھیں کہ عَبَسَ کسی اور کے متعلق ہے اور مَایُدْرِیْکَ رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے.یہ چار ہی صورتیں ہیں جو بن سکتی ہیں اور ہمیں یہ تعیین کرنا ہے کہ اِن چاروں میں سے اصل بات کیا ہے.پہلے ہم اس بات کو لے لیتے ہیں کہ یہاں رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہی نہیں عَبَسَ بھی غیر نے کیااور مَایُدْرِیْکَ بھی غیر سے تعلق رکھتا ہے مگر اس طرح چونکہ آیات کے معنے بالکل غیر معقول ہو جاتے ہیں اس لئے ہمیں ان میں
Page 233
پڑنے کی ضرورت نہیں.روایات نہایت تواتر سے ابنِ ام مکتوم کا قصہ بیان کرتی ہیں اور جس قصہ کو اِتنے تواتر اور تکرار کے ساتھ مختلف کتب میں بیان کیا جائے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا.بہرحال ماننا پڑتا ہے کہ کوئی واقعہ ہوا ضرور ہے.پس اگر ہم عَبَسَ اور مَایُدْرِیْکَ دونوں کسی غیر کے متعلق قرار دیں تو اس قصّہ کو سرے سے جھوٹا کہنا پڑتا ہے اور یہ بات بظاہر ناممکن ہے.ہم احادیث اور تاریخ دونوں میں اس واقعہ کا تکرار کے ساتھ ذکر پاتے ہیں اس لئے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ عَبَسَ رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم کے متعلق نہیں بلکہ کسی اور کے متعلق ہے.اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر ہم عَبَسَ بھی رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم کے متعلق سمجھ لیتے ہیں اور مَایُدْرِیْکَ میں بھی رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم کو مخاطب سمجھ لیتے ہیں.مگر پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے ضمائر کو کیوں بدلا.پہلے اُس نے عَبَسَ وَ تَوَلّٰۤى کیوں کہا اور پھر اُس نے مَایُدْرِیْکَ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیوںکیا؟ مفسّرین اس موقعہ پر بیان کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے عَبَسَ وَ تَوَلّٰۤىمیں رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم کا لحاظ کر کے غائب کے صیغے استعمال فرمائے ہیں اگر مخاطب کے صیغے استعمال کئے جاتے تو آپ کو زیادہ تکلیف ہوتی اس لئے خدا تعالیٰ نے یہ خیال کر کے کہ آپ کو بُرا نہ لگے عَبَسْتَ وَتَوَلَّیْتَ اَنْ جَآئَ کَ الْاَعْمٰی نہیں فرمایا بلکہ عَبَسَ وَ تَوَلّٰۤى.اَنْ جَآءَهُ الْاَعْمٰى فرمایا.پھر ذرا اعتاب کم ہو گیا تو مَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّهٗ يَزَّكّٰۤى سے آپ کو خطاب شروع کر دیا.لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اگلی آیتوں میں عتاب زیادہ ہے کم نہیں ہے.اور عَبَسَ وَ تَوَلّٰۤىمیں تو عتاب ہے ہی نہیں.جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ ایک اندھے کے سامنے عَبُوْس اور تَوَلّٰٓی سے کام لینا ہر گز کوئی ایسا فعل نہیں ہے جس سے اس کی دلآزاری ہو اور نہ یہ فعل ایسا ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عتاب نازل ہونے کا امکان ہو.بلکہ یہ تو آپ کے اعلیٰ درجہ کےاخلاق کا ایک ثبوت تھا.پس یہ عجیب بات ہے کہ جہاں عتاب نہیں تھا وہاں تواُس نے غائب کے صیغے استعمال کئے اور جہاں بہت زیادہ عتاب تھا وہاں اُس نے مخاطب کے صیغے استعمال کرنے شروع کر دئے.آخر یہ کتنے سخت الفاظ ہیں کہ اَمَّا مَنِ اسْتَغْنٰى.فَاَنْتَ لَهٗ تَصَدّٰى.وَ مَا عَلَيْكَ اَلَّا يَزَّكّٰى.وَ اَمَّا مَنْ جَآءَكَ يَسْعٰى.وَ هُوَ يَخْشٰى.فَاَنْتَ عَنْهُ تَلَهّٰى.کہ جوشخص مستغنی ہے تو اُس کی طرف پوری توجہ دیتا ہے حالانکہ تجھ پر کوئی اعتراض نہیں اگر وہ پاک نہ ہو اور جو تیری طرف دوڑتا آتا ہے اور وہ ڈرتا بھی ہے تُو اس سے بے رغبتی ظاہر کرتا ہے.کیا یہ عبوس اور تولّی سے کم خطرناک الفاظ ہیں؟ پس جہاں واقعہ میں توبیخ کا موقع تھا وہاں تو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کے صیغے استعمال کر دیئے اورجہاں توبیخ کا کوئی موقع ہی نہیں تھا بلکہ تعریف کا موقع تھا وہاں اس نے غائب کے صیغے رکھ دئے.گویا تعریف کو تو نظر انداز کر دیا اور توبیخ کے پہلو کو نمایاں کر دیا.پس یہ توجیہہ جو مفسّرین کی طرف سے کی جاتی ہے بالکل غلط ہے اور
Page 234
ان کے معنوں کو تسلیم کرتے ہوئے ضمائر کے بدلنے کی کوئی وجہ نہیں نظر آتی.اب دوہی صورتیں رہ جاتی ہیں جن میں سے پہلی یہ ہے کہ عَبَسَ وَ تَوَلّٰۤى ہم کسی غیر کے متعلق سمجھیں اور مَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّهٗ يَزَّكّٰۤىرسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرار دیں.مگر اس صورت میں جیسا کہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں یہ مشکل پیش آتی ہے کہ ہمیں اس واقعہ کا انکار کرنا پڑتا ہے جو ابن اُم مکتوم کے متعلق احادیث اور تاریخ کی کتابوں میں پایا جاتا ہے.حالانکہ یہ واقعہ ایسا ہے جس کا اس قدر شہادات کے بعد کسی صورت میں بھی انکار نہیں کیا جا سکتا متواتر تاریخی کتب میں اس واقعہ کو دوہرایا گیا ہے اور صحاح ستہ کی بعض کتب میں بھی یہ واقعہ پایا جاتا ہے (ترمذی ابواب التفسیر،باب سورۃ عبس) پس اگر ہم عَبَسَ وَ تَوَلّٰۤى کو رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم کے متعلق نہ سمجھیں تو ایک بہت بڑے تاریخی واقعہ کو غلط قرار دینا پڑتا ہے.حالانکہ تاریخی ثبوت اُس وقت تک ردّ نہیں کیا جا سکتا جب تک کوئی ویسا ہی اہم ثبوت اس کی تردید نہ کر دے.اب صرف چوتھی صورت ہی رہ جاتی ہے کہ عَبَسَ وَ تَوَلّٰۤى رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم کے متعلق سمجھیں اور مَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّهٗ يَزَّكّٰۤى کا خطاب کسی اور سے قرار دیں.اور میرے نزدیک یہی صورت ایسی ہے جس سے اس مشکل کا حل ہو سکتا ہے اس طرح قصّہ کی بناوٹ پر جوزد پڑتی ہے وہ دُور ہو جاتی ہے اور رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم کے مقام اور آپ کی شان پر بھی کوئی اعتراض واقع نہیں ہو سکتا.پس میرے نزدیک عَبَسَ وَ تَوَلّٰۤى رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ابن اُم مکتوم کا واقعہ بالکل صحیح ہے کیونکہ تواتر اور تکرار سے یہ واقعہ مختلف کتب میں بیان کیا گیا ہے اور ہم بغیر کسی قطعی اور یقینی ثبوت کے جو تاریخی شہادت بھی اپنے اندر رکھتا ہو اس واقعہ کو ردّ نہیں کر سکتے.بہرحال ابن اُم مکتوم آئے اور اُس وقت آئے جب رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم کفار مکّہ کے بڑے بڑے رئوسا ءکو تبلیغ کر رہے تھے.اُنہیں یہ دیکھ کر جوش پیدا ہوا کہ رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم اِن کفار پر اپنے قیمتی وقت کو کیوں ضائع کر رہے ہیں.دنیا میں مختلف طبائع ہوتی ہیں اور وہ اپنے اپنے رنگ میں خیالات کا اظہار کر دیتی ہیں.میں نے احمدیوں میں بھی دیکھا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جب اُنہیں معلوم ہو کہ کسی شدید دشمن کو تبلیغ کی جا رہی ہے تو وہ اُس وقت برداشت نہیں کر سکتے.اور وہ کہتے ہیں کہ جانے بھی دو یہ مردود لوگ ہیں یہ مُنہ لگانے کے قابل نہیں یہ تو دوزخ کی آگ میں جلنے والے ہیں ان پر اپنا وقت ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے.گویا دشمن کو دیکھ کر اُن کی طبیعت میں ایسا جوش پیدا ہوتا ہے کہ وہ یہ برداشت ہی نہیں کر سکتے کہ اُن سے باتیں کیوںکی جا رہی ہیں.اُن کا نقطۂ نگاہ یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ تو جہنم کا ایندھن ہیں اِسی مخالفت کی حالت میں مریں گے اور خدا کے غضب کے مستحق ہوں گے انہیں تبلیغ کرنا.خدا اور اس کے رسول
Page 235
کی باتیں سمجھانا اپنے وقت کو ضائع کرنے کے مترادف ہے.میں سمجھتا ہوں کہ عبداللہ بن ام مکتوم کی طبیعت بھی ایسی ہی ہو گی.جب وہ وہاں پہنچے اور انہوں نے دیکھا کہ رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم عتبہ اور شیبہ اور ابو جہل اور امیہ اور ولید وغیرہ کو تبلیغ کر رہے ہیں تو اُن کا جوش بھڑک اٹھا اور ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ خبیث دشمن جو رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم کو دن رات گالیاں دینے والے ہیں آپ کی مجلس میں آ کر کیوں بیٹھے ہیں یہ تو جہنم کی آگ کے مورد ہیں ان کا خدا اور اس کے رسول کی باتوں سے کیا تعلق ہے اور ان پر اپنے وقت کو ضائع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں.یہ اُ ن کے دل کے خیالات تھے اور انہی خیالات کے نتیجہ میں انہوں نے رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں دخل دینا شروع کر دیا کہ یا رسول اللہ! آپ عتبہ اور شیبہ اور ابوجہل وغیرہ کو اسلام کی باتیں کیوں بتا رہے ہیں اَقْرِئْنِیْ وَعَلِّمْنِیْ مِمَّا عَلَّمَکَ اللّٰہُ تَعَالٰی.ان کو دفع کریں اور میری طرف آپ توجہ کریں.رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم کو اُن کا اس طرح دخل دینا سخت ناگوار گزرا کہ باہر سے مہمان آئے ہوئے ہیں میں اُن سے گفتگو کر رہا ہوں اور میرا ہی ایک مرید حد سے متجاوز ہوتا جا رہا ہے اور ایسا رویّہ اختیار کر رہا ہے جو ان مہمانوں کی دل آزاری اور دل شکنی کا موجب ہے.اور گو انہوں نے اس وقت کفار کو کوئی گالی نہیں دی مگر بہرحال جب انہوں نے کہہ دیا کہ آپ میری طرف توجہ کریں تو اس کے معنے یہی تھے کہ ان لوگوں کوآپ دفع کریں یہ تو اسلام کے شدید دشمن ہیں انہوں نے اسلام کے احکام کو کہاں ماننا ہے.مگر رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے کہ یہ لوگ خواہ مانیں یا نہ مانیں میرا فرض ہے کہ میں ان کے کانوں تک تمام باتیں پہنچا دُوں اور خدا کے حضور بری الذمہ ہو جائوں.غرض عبداللہ بن ام مکتوم نے اپنے جوش میں ایک ایسی حرکت کی جو عقل اور تہذیب کے بالکل خلاف تھی.جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تبلیغ کر رہے تھے تو اُن کا کوئی حق نہیںتھا کہ وہ یہ سمجھ لیتے کہ ان کو تبلیغ بے فائدہ ہے آپ کو چاہیے اُن کو چھوڑ کر میری طرف توجہ کریں.اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ لوگ بعد میں واقع میں جہنمی ہی ثابت ہوئے اور رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے مگر اُس وقت تو رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم کا یہی فرض تھا کہ آپ آنیوالے مہمانوں کی عزت کریں.ان کی طرف توجہ کریں اور اُن سے عزت واحترام کے ساتھ باتیں کریں.لیکن عبداللہ بن اُم مکتوم کے دل میں خدا تعالیٰ کے احکام کا وہ ادب نہیں ہو سکتا تھا جو رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھا.اور نہ اُن کو اکرامِ ضعیف کا اس قدر احساس ہو سکتا تھا جتنا رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم کو اس کا احساس تھا خصوصًا اندھے میں تو یہ احساس بہت کم ہوتا ہے چونکہ اسے کچھ نظر نہیں آتا اس لئے وہ دوسروں کو کھری کھری سُنا دیتا ہے.ہمارے ملک میں بھی کہتے ہیں کہ اگر کھری کھری باتیں سُننی ہوں تو کسی اندھے سے جا کر سُن لو.اسکی وجہ یہی ہے کہ چونکہ اندھے کو نظر نہیں آتا اس
Page 236
لئے اُسے اس بات کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی کہ لوگوں پر اس کی بات کا کیا اثر ہو رہا ہے.غرض عبداللہ بن اُم مکتوم رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے اور جب انہوں نے دیکھا کہ آپ اشد ترین دشمن کفار کو تبلیغ کر رہے ہیں تو اُن کی طبعیت میں سخت جوش پیدا ہوارسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں اور اُن سے بھی یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ تم یہاں سے نکلو تمہارا یہاں کیا کام؟ آخر انہوں نے سوچ کر یہی کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا شروع کر دیا کہ یارسول اللہ! اَقْرِئْنِیْ وَعَلِّمْنِیْ مِمَّا عَلَّمَکَ اللّٰہُ تَعَالیٰ اور اس کو بار بار دُوہرایا اُن کی یہ بات رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم کو پسند نہ آئی.دوسری طرف آپ یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ اُن کا دل ٹوٹے اس لئے اُس وقت آپ نے عبوس اور تولّی سے کام لیا.آپ نے خیال فرمایا کہ آخریہ کفار کے رئوساء کیا کہیں گے کہ یہ مسلمان ایسے تہذیب سے ناآشنا ہیں کہ آداب مجلس کا بھی خیال نہیں رکھتے اور یہ بھی نہیں دیکھتے کہ کوئی شخص اُن کے پاس اُن کی باتیں سُننے کے لئے آیا ہوا ہے.خواہ وہ منافقت سے آئے تھے.خواہ دل میں وہ آپ کی باتوں کو جھوٹا ہی کہتے جاتے تھے مگر چونکہ وہ ظاہر یہ کرتے تھے کہ ہم اسلام کی باتیں سننے کے لئے آئے ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سمجھتے تھے کہ ان کو تبلیغ کرنا ضروری ہے اس لئے آپ نے ابن اُم مکتوم کی دخل اندازی پر عبوس کیا اور تولّی کی.اس واقعہ کی طرف ان آیا ت میں اشارہ کیا گیا ہے.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عَبَسَ وَ تَوَلّٰۤى ہمارے رسول نے عبوس کیا اور تولّٰی کی.اَنْ جَآءَهُ الْاَعْمٰى اس موقعہ پر کہ آپ کے پاس ایک اندھا آیا.اَلْاَعْمٰی کا لفظ بھی بتلاتا ہے کہ یہاںکسی خاص واقعہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور اَلْاَعْمٰی سے کوئی خاص اندھا مراد ہے.اگر اس جگہ اس اندھے کی تعریف کرنے کا موقعہ ہوتا اور یہ کہنا ہوتا کہ اُس اندھے کی طرف کیوں توجہ نہیں کی گئی یا اُس اندھے نے جو فعل کیا تھا وہ بڑا قابل تعریف تھا تو بجائے اَلْاَعْمٰی کہنے کے اس کا نام لیا جاتا اور کہا جاتا کہ فلاں شخص آیا مگر رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم نے عبوس اور تولّٰی سے کام لیا.لیکن اس جگہ چونکہ زد ایک اندھے پر پڑتی تھی اس لئے اس کا نام نہیں لیا گیا اور اَعْمٰی کہہ کر اشارہ کر دیا کہ یہاں ایک خاص واقعہ کا ہم ذکر کر رہے ہیں.اس وجہ سےاَعْمٰی کے ساتھ اَلْ لگا دیا.اوراس طرح ایک مخصوص اندھے کی طرف اشارہ کیا گیا پس اللہ تعالیٰ کا اَلْاَعْمٰی کہنا بتا رہا ہے کہ اس واقعہ کی زد اُس اعمیٰ پر ہی پڑتی تھی تبھی اُس کا نام نہیں لیا گیا.ورنہ اگر یہ تعریف کا موقع ہوتا تو اللہ تعالیٰ ضرور نام لیتا.اور کہتا کہ عَبَسَ وَتَوَلّٰٓی اَنْ جَآئَ ہُ عَبْدُاللّٰہِ ابْنُ اُمِّ مَکْتُوْمٍ.مگر اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا.اِدھر رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم کے متعلق صرف عَبَسَ وَ تَوَلّٰۤى کے الفاظ رکھ دئے کیونکہ ان دونوں میں آپ کے اعلیٰ درجہ کے اخلاق کی تعریف کی گئی ہے.
Page 237
میرے نزدیک واقعہ یہ ہے کہ عبداللہ بن اُمّ مکتوم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے اور انہوں نے ایسے رنگ میں سوال کیا جو دوسروں کی دل شکنی کا باعث تھا اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کا کلام بھی قطع ہوتا تھا.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن پر اپنی ناراضگی کو ظاہر نہیں ہونے دیا.صرف اتنا ہوا کہ آپ نے ماتھے پر تیوری چڑھائی.اور اُس کی طرف سے مُنہ پھیر لیا اور یہ دونوں باتیں ایسی ہیں جن کو ایک اندھا شخص دیکھ نہیں سکتا جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی باتیں جاری رکھیں اور عبداللہ بن اُم مکتوم کی طرف کوئی توجہ نہ کی تو وہ غُصّہ میں اُٹھ کر چلے گئے.ممکن ہے انہوں نے بعض اور لوگوں کے پاس بھی اس بات کو بیان کیا ہو اور ممکن ہے جن کے پاس انہوں نے اس واقعہ کا ذکر کیا ہو ان کی طبیعت بھی اسی قسم کی جوش والی ہو اور ان کے دل میںبھی یہ میں خیال پیدا ہوا ہو کہ یہ بات اچھی نہیں ہوئی.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف توجہ کرنی چاہیے یہ خبیث دشمن کون ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آکر بیٹھ جاتے ہیں اور آپ کے وقت کو ضائع کرتے ہیں.پس عَبَسَ وَ تَوَلّٰۤى میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا گیا ہے اور مَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّهٗ يَزَّكّٰۤى میں عبداللہ بن ام مکتوم کی طرح کے خیالات رکھنے والے لوگوں کو مخاطب کیا گیا ہے.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہمارے اس رسول نے ایک اندھے کے بیجا دخل دینے پر عبوست کی اور بڑے اعلیٰ درجہ کے اخلاق کا ثبوت دیا اور ہمارے اس رسول نے صرف تولّٰی کی اور بڑے اعلیٰ درجہ کے اخلاق کا ثبوت دیا تا کہ غصّہ اور ناراضگی کی حالت میں بات بڑھ نہ جائے.٭ ٭نوٹ: عَبَسَ وَ تَوَلّٰی سے کَلَّا اِنَّھَا تَذْکِرَۃٌ تک کی آیات کا ترجمہ متن میں اس مضمون کے مطابق نہیں کیا گیا جو آیت نمبر۲ ،۳میں بیان ہو چکا ہے ان آیات کا ترجمہ ایک اور مضمون کے مطابق کیا گیا جو کہ آیت نمبر ۱۲ کے ماتحت درج کیا گیا ہے.آیت نمبر۲،۳ کے ماتحت کی گئی تفسیر کے مطابق ان آیات کا ترجمہ یوں ہو جاتا ہے.’’وہ چیںبجبیں ہوا اور (اس کی طرف سے) مُنہ موڑ لیا.اس وجہ سے کہ اس کے پاس ایک نابینا (جسے واقف لوگ جانتے ہیں) آیا اور اے معترض کون سی بات تجھے (اس پر) آگاہ کر سکتی ہے کہ وہ ضرور پاک ہو جائے گا یا (موجبات عبرت کو) یاد کرے گا تو (یہ)یادکرنا اُسے نفع بخش دے گا وہ شخص جو بے پروائی کرتا ہے تو تُو (اس کی طرف) خوب توجہ کرتا ہے حالانکہ تجھ پر (اس وجہ سے) کوئی الزام نہیں کہ وہ پاک نہ ہو گا.اور جوتیری طرف دوڑتا ہواآتا ہے اور وہ (ساتھ ہی خُدا سے) ڈرتا بھی ہے تو تُو اس سے بے اعتنائی کرتا ہے.ہرگز نہیں یقیناً یہ (قرآن) تو ایک نصیحت ہے.‘‘
Page 238
وَ مَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّهٗ يَزَّكّٰۤىۙ۰۰۴اَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ اور (اے رسول) کون سی بات تجھے(اس پر)آگاہ کر سکتی ہے کہ وہ ضرور پاک ہو جائے گا یا (موجبات عبرت کو) الذِّكْرٰىؕ۰۰۵ یاد کرے گا تو (یہ) یاد کرنا اُسے نفع بخش دے گا.٭ حَلّ لُغَات.مَایُدْرِیْکَ.یُدْرِیْکَ یُدْرِیْ اور ک سے مرکب ہے.یُدْرِیْ اَدْرٰی کا مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اور کاف ضمیر کا ہے.اَدْرٰی کے معنے ہیں اَعْلَمَہُ.اُس کو بتایا (اقرب) یُدْرِیْکَ کے معنے ہوں گے اس نے تجھ کو بتایا ہےاور مَا یُدْرِیْکَ کے معنے ہوں گے کس نے تجھے بتایا ہے؟ نیز عرب لوگ جب کہتے ہیں مَایُدْرِیْکَ تو بسا اوقات مراد یہ ہوتی ہے کہ مَاتَدْرِیْ یعنی تو نہیں جانتا.تجھے اس کا علم نہیں؟ یَزَّکّٰی یَزَّکّٰی اصل میں یَتَزَّکّٰی ہے تاء کا زاء میں ادغام کر دیا گیا اور یَتَزَّکّٰی سے یَزَّکّٰی ہو گیا.تَزَکّٰی فُلَانٌ کے معنے ہوتے ہیں.صَارَزَکِیًّا وہ پاک ہو گیا (اقرب) اور یَتَزَکّٰی کے معنے ہوں گے.وہ پاک ہو جاتا ہے.اور لَعَلَّہٗ یَتَزَّکّٰی کے معنے ہوں گے کہ اُس کے لئے ممکن ہے کہ وہ ہدایت پا جائے.یَذَّکَّرُ.یَذَّکَّرُ اصل میں یَتَذَکَّرُ ہے.تَاء کو ذال میں ادغام کر دیا گیا.اور یَذَّکَّرُ ہو گیا.یَتَذَکَّرُ تَذَکَّرَ سے مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے.اور تَذَکَّرَ الشَّیْئَ کے معنے ہیں حَفِظَہُ فِیْ ذِھْنِہٖ کسی چیز کو اپنے ذہن میں محفوظ کر لیا.اور جب تَذَکَّرَ مَا کَانَ قَدْ نَسِیَ کہیں تو معنے ہوں گے فَطِنَ بِہٖ کسی بھولی ہوئی بات کو یاد کر لیا.(اقرب) پس یَتَذَکَّرُ کے معنے ہوں گے.کسی نصیحت والی بات کو ذہن میں وہ مخفوظ کر لے (۲) یا کسی نصیحت والی بُھولی ہوئی بات کو یاد کر لے.تفسیر.اس آیت کے صاف معنے یہ ہیں کہ تجھ کو کس نے بتایا کہ وہ شخص ہدایت پا جاتا.مگر مفسّرین اس کے معنے یہ کرتے ہیں کہ تجھ کو کس نے بتایا کہ وہ ہدایت نہ پاتا.پھر وہ کہتے ہیں مَایُدْرِیْکَ الگ جملہ ہے اور لَعَلَّہٗ یَزَّکّٰی الگ جملہ ہے.گویا اس کے معنے وہ اس رنگ میں کرتے ہیں کہ مَایُدْرِیْکَ تجھے کس نے بتایا ہے کہ وہ ہدایت نہ پاتا لَعَلَّہٗ یَزَّکّٰی شاید وہ ہدایت پا جاتا.حالانکہ اس آیت کے صاف معنے یہ ہیں کہ تجھے کس نے بتایا کہ وہ شخص ضرور ٭نوٹ.لَعَلَّ کا ترجمہ ’’ضرور‘‘ کے لفظ سے کیا گیا ہے اس لئے کہ لَعَلَّ کلام ملوک کے طور پر استعمال ہوتا ہے یعنی بادشاہ کے لئے کوئی اور یا بادشاہ اپنی نسبت خود امید اور توقع کے الفاظ استعمال کرتا ہے لیکن مراد اس سے یقینی بات یا حکم کے ہوتی ہے.
Page 239
فائدہ اٹھاتا.یہاں یُدْرِیْکَ سے مراد وہ خیال ہو گا جو بعض مسلمانوں کے دل میں اُس وقت پیدا ہوا یا ہو سکتا تھا.پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے معترض تجھے کس نے بتایا ہے کہ اگر عبداللہ بن ام مکتوم کی طرف توجہ کی جاتی تو وہ ضرور فائدہ اٹھاتا.آخر لوگ مرتد بھی ہو جاتے ہیں اور باوجود ایمان کے بڑے بڑے دعووں کے اُن پر بعض دفعہ ایسا وقت بھی آجاتا ہے جب اُن کی تمام کوششیں ایمان کے خلاف صرف ہونے لگ جاتی ہیں.پس جب حالت یہ ہے اور تغیّرات کے مختلف دور آتے رہتے ہیں تو تمہارے پاس کون سا ذریعہ ایسا ہے جس سے تمہیںپتہ لگ گیا کہ فلاں شخص کی طرف توجہ کرنا زیادہ مفید تھا.انبیاء کا مقام بیشک ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ کسی شخص سے کوئی بات کہیں تو خواہ وہ کیسے ہی اہم کام میں مشغول ہو اور خواہ اس کو ترک کرنا کتنا ہی تکلیف دِہ ہو اس کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اس کام کو ترک کر دے اور نبی کی بات سننے کی طرف متوجہ ہو جائے اور درحقیقت یہی ایمان کی علامت ہے خدا کے رسول کی آواز کے بعد کسی انسان کا کوئی حق نہیں رہتا کہ وہ دوسرے امور کی طرف متوجہ رہے.پس مقامِ نبوت رکھنے والا انسان یا اُس کا نائب اگر کسی شخص کو اپنی طرف متوجہ کرے اور وہ شخص مثلاً اُس وقت کسی کو تبلیغ کر رہا ہو تو خواہ قطع کلامی کو لوگ بدتہذیبی سمجھیں اس کا فرض ہو گا کہ وہ تبلیغ کو بند کر دے اور خدا کے رسول اور اس کے نائب کی بات سننے کی طرف متوجہ ہو جائے.اگر ابن ام مکتوم تبلیغ کر رہے ہوتے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اُن کو بلاتے تو اُن کا فرض تھا کہ وہ تبلیغ کو چھوڑ دیتے اور اس بات کی پروا نہ کرتے کہ اگر میں نے ایسا کیا تو اس کو تہذیب کے خلاف سمجھا جائے گا.مگر عبداللہ بن ام مکتوم کو یہ مقام حاصل نہیں تھا کہ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا تو آپ اُس کی طرف ضرور متوجہ ہوجاتے اور دوسروں کو تبلیغ چھوڑ دیتے.یہ بھی ایک قیاس تھا کہ اگر کفار کی طرف توجہ کی گئی تو ان کو فائدہ نہ ہوگا.اور یہ بھی ایک قیاس تھا کہ اگر عبداللہ بن ام مکتوم کی طرف توجہ کی جاتی تو اُسے فائدہ ہوتا.کوئی قطعی اور یقینی بات نہیںتھی اور جب یہ دونوں قیاسی باتیں تھیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض تھا کہ اخلاق جس بات کی تائید میں تھے اس کو اختیار کرتے اور جس بات کی اخلاق اجازت نہیں دیتے اس کی طرف توجہ نہ کرتے اسی وجہ سےآپ نے عبداللہ بن ام مکتوم کی طرف تو توجہ نہ کی اور کفار کی طرف ہی تمام توجہ رکھی.پس مَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّهٗ يَزَّكّٰۤىمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اے معترض تُو جو کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلطی کی تجھے کس نے بتایا ہے کہ ابن اُم مکتوم کے لئے تزکیہ حاصل کرنا ممکن تھا دوسرے کے لئے نہیں.یہ اور بات ہے کہ اُس نے بعد میں تزکیہ حاصل کر لیا مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پتہ تھا کہ کل اس کا کیا انجام ہو گا اور یہ ہدایت پر قائم بھی رہے گا یا نہیں.بہرحال جب خدا نے کہا ہے کہ جو شخص تمہارے گھر میں آئے تم اس کا احترا م کرو اور جب خدا
Page 240
نے یہ کہا ہے کہ جو بات مقدم ہو اُس کو مقدم رکھو اور جو مؤخر ہو اس کو مؤخر رکھو تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم مقدم کو مؤخر اور مؤخر کو مقدم کس طرح کر سکتے تھے؟ اور کس طرح فیصلہ کر سکتے تھے کہ عبداللہ بن ام مکتوم کی طرف اگر توجہ کی گئی تو وہ ضرور پاک ہو جائے گا.اَوْيَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرٰى یا یہ بھی کس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو سکتا تھا کہ اگر اُسے کچھ نصیحت کی باتیں بتائی گئیں تو وہ اُن سے فائدہ اٹھا لے گا؟ ممکن ہے کوئی شخص کہہ دیتا کہ اگر زیادہ نہ سہی تو عبداللہ بن ام مکتوم کچھ تو فائدہ اٹھا لیتے.مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں اس بات کا بھی کیا علم ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ فائدہ اٹھاتا یا نہ اٹھاتا؟ یہ بھی ایک قیاس ہے اور وہ بھی ایک قیاس ہے.اور جب دو قیاس جمع ہو گئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس قیاس کو ترجیح دے دی جس کے ترجیح دینے سے اکرامِ ضیعف میں بھی کوئی نقص واقع نہیں ہو سکتا تھا.اور خدا تعالیٰ کا یہ قانون بھی پورا ہو جاتا تھا کہ مقدم کو مقدم اور مؤخر کو مؤخر رکھو.اَمَّا مَنِ اسْتَغْنٰىۙ۰۰۶فَاَنْتَ لَهٗ تَصَدّٰىؕ۰۰۷وَ مَا عَلَيْكَ (کیا) جو شخص (حق سے) بے پرواہی کرتا ہے.(اس کی طرف) تو تُو خوب توجہ کرتا ہے؟ حالانکہ تجھ پر اَلَّا يَزَّكّٰىؕ۰۰۸ (اس وجہ سے) کوئی الزام نہیں کہ وہ پاک نہ ہو گا.حَلّ لُغَات.اِسْتَغْنٰی اِسْتَغْنٰی غَنِیَ سے باب استفعال ہے.غَنِیَ غِنًا کے معنے ہوتے ہیں.وہ مالدار ہو گیا.اور اِسْتَغْنٰی کے معنے ہوں گے.اُس نے چاہا کہ وہ مالدار ہو جائے.نیز اِسْتَغْنٰی عَنْہُ بِہٖ کے معنے ہوتے ہیں اِکْتَفٰی اُس نے ایک چیز کے مل جانے سے دوسری سے لاپرواہی کی (اقرب) پس اَمَّا مَنِ اسْتَغْنٰی کے معنے ہوں گے وہ جو مال کا طالب ہے (۲) وہ جو لاپرواہی کرتا ہے.تَصَدّٰی تَصَدّٰی اصل میں تَتَصَدّٰی ہے جو تَصَدّٰی کا مضارع ہے.تَصَدّٰی لَہٗ کے معنے ہیں تَعَرَّضَ وَھُوَالَّذِیْ یَسْتَشْرِفُہٗ نَاظِرًااِلَیْہِ.کسی چیز کے سامنے آیا.اور شوق سے اس کو دیکھا.اور تَصَدّٰی لِلْاَمْرِ کہیں تو معنے ہوں گے رَفَعَ رَاْسَہُ اِلَیْہِ اپنا سر اس کی طرف توجہ کے لئے اٹھایا (اقرب) پس تَصَدّٰی کے معنے ہوں گے.تُو اس کے سامنے آتا ہے (۲) تُو اس کی طرف توجہ دیتا ہے.تفسیر.یہاں عام انسانوں کی حالت بیان کرتے ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنے
Page 241
والوں کا اپنا حال بیان کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ ان کی اپنی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ بڑے لوگوں کی طرف تو توجہ کرتے ہیں لیکن چھوٹے درجہ کے آدمیوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں.گویا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنے والوں کو ان کی اپنی حالت کی طرف توجہ دلائی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ اے معترض! تو محمد رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ کہتا ہے کہ جو مستغنی ہوتا ہے اس کی طرف وہ زیادہ توجہ کرتے ہیں اور جو غریب اور معمولی درجہ کا آدمی ہوتا ہے اس کی طرف وہ کوئی توجہ نہیں کرتے.حالانکہ اے معترض تُو جو کچھ کہہ رہا ہے یہ تیری اپنی حالت ہے اور تیرا ذاتی رویّہ واقعہ میں ایسا ہی ہے کہ تو اُمراء کی طرف توجہ کرتا ہے اور غرباء کو نظر انداز کر دیتا ہے مگر تُو اپنی اس حالت کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتا ہے اور جو الزام خود تجھ پر عائد ہوتا ہے وہ تُو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لگا رہا ہے.تُو اپنے حالات پر غور کر اور دیکھ کہ کیا یہ سچ نہیں کہ اَمَّا مَنِ اسْتَغْنٰى.فَاَنْتَ لَهٗ تَصَدّٰى جو شخص امیر ہوتا ہے تیری ساری توجہ کا وہ مرکز بن جاتا ہے تَصَدّٰی دراصل تَتَصَدّٰی ہے وَمَا عَلَیْکَ اَلَّایَّزَّکّٰی حالانکہ تجھ پر اس بات کی کوئی ذمہ واری نہیں کہ کون شخص ہدایت پاتا ہے اور کون نہیں پاتا.تمہیں خدا تعالیٰ کے قانون کا احترام مدنظر رکھنا چاہیے اور جو کچھ خدا کہےاس پر اپنی ذاتی خواہشات کو قربان کر دینا چاہیے خدا کہے کہ مومن سے بات کرو تو تم مومن سے بات کرو اور اگر خدا کہے کہ کافر سے بات کروتو تم کافر سے بات کرو.مگر تم توعمدًااور ارادتًا اُنہی کی طرف توجہ کرتے ہو جو امراء میں شامل ہوتے ہیں حالانکہ یہ صرف خدا کو ہی پتہ ہے کہ کس نے نَازِعَات میں سے بننا ہے اور کس نے نَاشِطَات میں سے بننا ہے.تمہارا کام یہی ہے کہ جو خدا تعالیٰ کے مقررہ قواعد ہیں اُن پر عمل کرو.خدا تعالیٰ نے اکرام ضیف کا حکم دیا ہے تم اکرامِ ضیف کو ملحوظ رکھو.خدا تعالیٰ نے مقدم کو مقدم اور مؤخر کو مؤخر رکھنے کا حکم دیا ہے تمہارافرض ہے کہ تم بھی ایسا ہی کرو اور اس بات کو نظر انداز کر دو کہ فلاں امیر ہے اور فلاں غریب.مگر تمہاری حالت یہ ہے کہ تم امراء کی طرف توجہ رکھتے ہو اور پھر کہتے یہ ہو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے ہیں حالانکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو کچھ کیا خدائی منشاء کے مطابق کیا.اس کے احکام کو انہوں نے ملحوظ رکھا.اس کے اوامر کو انہوں نے تسلیم کیا اور اُس کے قوانین کو نظر انداز نہیں ہونے دیا.مگر تم بجائے اپنی حالت پر غور کرنے کے یہ نقص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر رہے ہو.حالانکہ انہوں نے جو کچھ کیا بالکل بجا اور درست کیا.
Page 242
وَ اَمَّا مَنْ جَآءَكَ يَسْعٰىۙ۰۰۹وَ هُوَ يَخْشٰىۙ۰۰۱۰فَاَنْتَ عَنْهُ اور( کیا) جو تیری طرف دوڑتا ہوا آتا ہے اور وہ( ساتھ ہی خدا سے) ڈرتا بھی ہے تو تو اس تَلَهّٰىۚ۰۰۱۱ سے بے اعتنائی کرتا ہے.حَلّ لُغَات.یَسْعٰی یَسْعیٰ سَعٰی سے مضارع کا صیغہ ہے اور سَعٰی کے معنے ہیںقَصَدَ اُس نے ارادہ کیا.اور جب سَعٰی الرَّجُلُ کہیں تو معنے ہوں گے مَشَی وَعَدَا یعنی وہ دوڑ کر چلا (اقرب) پس یَسْعٰی کے معنے ہوں گے وُہ دوڑ کر آتا ہے (۲)وہ قصد کرتا ہے.تَلَھّٰی تَلَھّٰی اصل میں تَتَلَھّٰی ہے جو تَلَھّٰی سے مضارع ہے اور تَتَلَھّٰی کے معنے ہیں تَتَشَاغَلُ تو ایک سے توجہ ہٹا کر دوسرے کی طرف متوجہ ہوتا ہے.(لسان) تفسیر.اس آیت میں خدا تعالیٰ نے کسی خاص واقعہ کی طرف اشارہ نہیں کیا مگر اس سے اتنا ضرور پتہ چلتا ہے کہ یہ آیت ابن ام مکتوم والے واقعہ پر چسپاں نہیں ہو سکتی کیونکہ ابن اُم مکتوم تو اندھے تھے وہ دوڑتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کس طرح آسکتے تھے.پھر ابن اُم مکتوم تو اتنے دلیر آدمی تھے کہ مکّہ کے بڑے بڑے رئوساء بیٹھے ہیں اور وہ آتے ہی اُن کو ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ خدا اور رسول کے دشمن یہاں بیٹھے ہی کیوں ہیں.یہ تو مردودلوگ ہیں ان کی طرف توجہ کرنا اپنے وقت کو ضائع کرنا ہے مگر یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَ هُوَ يَخْشٰى ساتھ ہی وہ ڈرتا بھی ہے.اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس واقعہ کا عبداللہ بن ام مکتوم والے واقعہ سے کوئی تعلق نہیں.اس میں بھی درحقیقت لوگوں کے اندرونی اخلاق کا ایک عام نقشہ کھینچا گیا ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنےوالوں کو جواب دیا گیا ہے کہ تم ہمارے رسول پر کیا اعتراض کرتے ہو تمہاری تو اپنی حالت یہ ہے کہ تمھارے پاس اگر کوئی غریب شخص دوڑا دوڑا آئے تو تم اُس کی طرف منہ بھی نہیں کرتے لیکن اگر کوئی امیر آجائے تو صرف اتنی بات پرہی خوش ہو جاتے ہو کہ وہ امیر تمہارے پاس چل کر آیا اور تم اس پر خوشی سے اپنے جامہ میں پُھولے نہیں سماتے.پس یہ تمہاری اپنی حالت ہے ہمارا رسول ایسا نہیں.ہمارے رسول کے متعلق یہ کہنا کہ وہ امیروں کی طرف زیادہ توجہ کرتا ہے اور غرباء کو نظر انداز کر دیتا ہے صریح ظلم ہے.ہاں تمہاری حالت یہی ہے اوراس
Page 243
کو ہم بھی تسلیم کرتے ہیں چنانچہ واقعہ میں اگر دُنیا پر غور کر کے دیکھا جائے تو لوگوں کے دلوں میں اس بات کی بڑی اہمیت ہوتی ہے کہ کسی امیر شخص سے اُنہیں گفتگو کرنے کا موقعہ مل جائے مگر اللہ تعالیٰ کے انبیاء ان باتوں کی ذرا بھی پروا نہیں کرتے.حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰ ۃ والسلام ایک دفعہ لاہور یا امرتسر کے سٹیشن پر تھے کہ پنڈت لیکھرام بھی وہاں آپہنچے اور اس نے آپ کوآکر سلام کیا.چونکہ پنڈت لیکھرام آریہ سماج میں بہت بڑی حیثیت رکھتے تھے اس لئے جو لوگ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ تھے وہ بہت خوش ہوئے کہ لیکھرام آپ کو سلام کرنے کے لئے آیا ہے.مگر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ان کی طرف ذرا بھی توجہ نہ کی اور جب یہ سمجھ کر کہ شاید آپ نے دیکھا نہیں کہ پنڈت لیکھرام صاحب سلام کر رہے ہیں آپ کو اس طرف توجہ دلائی گئی تو آپ نے بڑے جوش سے فرمایا کہ اسے شرم نہیں آتی کہ میرے آقا کو توگالیاں دیتا ہے اور مجھےآکر سلام کر تا ہے.گویا آپ نے اس بات کی ذرا بھی پَروا نہ کی کہ لیکھرام آیا ہے لیکن عام لوگوں کے نزدیک سب سے بڑی کامیابی یہی ہوتی ہے کہ کسی بڑے رئیس یا لیڈر سے اُن کو ملنے کا اتفاق ہو جائے.چنانچہ جب کوئی ایسا شخص اُن کے پاس آتا ہے وہ بڑی توجہ سے اُس سے ملتے ہیں لیکن اگر کوئی غریب شخص آ جائے تو پروا بھی نہیں کرتے.اللہ تعالیٰ معترضین کو اُن کے اسی نقص کی طرف توجہ دلاتا ہے اور بتاتا ہے کہ اَمَّا مَنْ جَآءَكَ يَسْعٰى.وَ هُوَ يَخْشٰى.فَاَنْتَ عَنْهُ تَلَهّٰى.تمہاری اپنی حالت یہ ہے کہ جو شخص تمہارے پاس دوڑتا ہوا آئے اور ساتھ ہی وہ اللہ تعالیٰ کی خشیت بھی اپنے دل میں رکھتا ہو لیکن امارت اس میں نہ ہو تم اُس سے غافل رہتے ہو.پس وہ لوگ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے اُن کو زجر کیا ہے کہ تم ہمارے رسول پر کیا اعتراض کرتے ہو جائو اور اپنے اخلاق کو دیکھو.تمہاری حالت یہ ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی بڑا آدمی آ جائے تو تم اس کی تعظیم کے لئے کھڑے ہو جاتے ہو.اس کی طرف تم اپنی تمام توجہ صرف کر دیتے ہو لیکن اگر کوئی مسکین اور غریب آدمی آ جائے تو تُم اس سے منہ پھیر لیتے ہو اور اُس سے بات تک کرنا گوارا نہیں کرتے.تمہارا اعتراض آخر کیا ہے یہی کہ عبداللہ بن ام مکتوم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ نے اس کی طرف توجہ نہ کی حالانکہ اُس وقت آپ کا اس کی طرف توجہ نہ کرنا ہی ضروری تھا.اُس نے مجلس میں آکر ایک نامناسب حرکت کی خلافِ اخلاق حرکت کی.خلافِ آداب حرکت کی اور وہ یقیناً اسی بات کا مستحق تھا کہ اس کی طرف توجہ نہ کی جاتی مگر تم اس پر اعتراض کر رہے ہو اور تم یہ نہیں دیکھتے کہ ایک جائز فعل پر تو اعتراض کر رہے ہواور تمہاری اپنی حالت یہ ہے کہ تم امیروں کی
Page 244
طرف ہی توجہ رکھتے ہو غریبوں کو اپنی خاطر میں ہی نہیں لاتے.ابن ام مکتوم کے آنے اور بیجا دخل پر عبوس و تولیٰ اختیار کرنے سے آنحضرت ؐ کے بہترین اخلاق کا اظہار غرض اُن چاروں باتوں میں سے جن کو میں تفصیل کے ساتھ اوپر بیان کر چکا ہوں اِس موقعہ پر ایک ہی بات چسپاں ہوتی ہے.میرے نزدیک عَبَسَ وَ تَوَلّٰۤى رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہی ہے اور میرے نزدیک ایک اندھے کے آنے پر آپ کاعبوس اور تولّی اختیار کرنا اعلیٰ درجے کا قابلِ تعریف فعل ہے اور یہ آیت بھی آپ کے اخلاق کی تعریف کے لئے ہی نازل ہوئی ہے مذّمت کے لئے نازل نہیں ہوئی.مذمّت والے معنے کر کے آیات کی ترتیب قائم ہی نہیں رہتی مَیں نے بتایا ہے کہ ان آیات میں غائب کے صیغے شروع ہوتے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد ہی مخاطب کے صیغے شروع ہو جاتے ہیں.صیغوں کی یہ تبدیلی کسی حکمت کے بغیر نہیں ہوسکتی اور وہ حکمت یہی ہے کہ پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی گئی ہے اور پھر کفار یا بعض نا تربیت یافتہ مسلمانوں کے دلوں میں اِس واقعہ سے جو وساوس پیدا ہوئے تھے یا ہو سکتے تھے اُن کا ازالہ کیا گیا ہے اوربتایا گیا ہےکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فعل اللہ تعالیٰ کے منشاء اور اُس کے احکام کے بالکل مطابق تھا آپؐ پر اعتراض کرنے والوں کی اپنی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ اُمراء اور غرباء میں تفاوت کرتے ہیں.وہ بڑوں اور چھوٹوں میں امتیاز روا رکھتے ہیں مگرہمارا رسول ایسا نہیں ہے پس عَبَسَ وَ تَوَلّٰۤى میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے کے بعد وَ مَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّهٗ يَزَّكّٰۤى میں معترضین کو مخاطب کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ تمہارا اعتراض بالکل بےہودہ ہے تمہیں کون سا یقینی علم اِس بات کا ہے کہ ابن اُم مکتوم کی طرف اگر توجہ کی جاتی تو وہ ضرور فائدہ اٹھاتا یا تمہیں کون سا الہام ہوا ہے کہ ابن ام مکتوم کا فائدہ اٹھانا زیادہ قرینِ قیاس تھا.صرف تمہارا قیاس ہی ہے کہ اس کی طرف توجہ کرنا زیادہ بہتر تھا.اور جب یہ صرف قیاس تھا کسی یقینی اور قطعی علم پر اِس کی بنیاد نہیں تھی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقدم کو مقدم رکھا اور اکرامِ ضیف کے حکم کو بھی نظر انداز نہ ہونے دیا اور ابن ام مکتوم کی دخل اندازی پر ایسے رنگ میں اظہار ناراضگی کیا جس سے اندھے کو کوئی خاص تکلیف نہیں ہو سکتی تھی.پس آپؐ نے جو کچھ کیا بالکل درست کیا.لیکن اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنے والو! تمہارے اپنے اخلاق یہی ہیں مگر تم الزام ہمارے رسول پر لگا رہے ہو.انبیاء ؑ پر الزام لگانا یا اُن پر کوئی بے جا اعتراض کرنا بہت خطرناک ہوتا ہے.کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء ؑکے متعلق بہت بڑی غیرت رکھتا ہے.اسی غیرت کا مظاہرہ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کیا ہے اور فرمایا ہے کہ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے ہو لیکن واقعہ یہ ہے کہ یہ کمزوری خود تمہارے اندر پائی جاتی ہے اور تمہارے اپنے
Page 245
اخلاق ایسے ہی ہیں.مَیں نے دیکھا ہے بیسیوں دفعہ منافق مجھ پر کئی قِسم کے اعتراض کرتے ہیں مَیں اُن کے جواب میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ یہ اعتراض تو صحیح ہیں مگر مجھ پر نہیں بلکہ خود تم پر پڑتے ہیں کیونکہ تمہارے اپنے اعمال بتا رہے ہیں کہ تم میں یہ یہ خرابیاں پائی جاتی ہیں.یہی طریق اللہ تعالیٰ نے اس جگہ اختیار کیا ہے کہ جہاں تک اس اعتراض کا تعلق ہے کہ بعض لوگ غریبوں کی طرف توجہ نہیں کرتے اور اُمراء کی طرف توجہ کر لیتے ہیں یہ تو بالکل صحیح اور درست ہے مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا بلکہ معترضین کے اندر بیشک یہ کمزوری پائی جاتی ہے اور ہم اِن کی اس کمزوری کو تسلیم کرتے ہیں.گویا ایک طرف اللہ تعالیٰ نے اس اعتراض کو صحیح قرار دے دیا اور دوسری طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جواعتراض کیا جاتا تھا اُس کو غلط قرار دے دیا اور مسلمانوں کو نصیحت کر دی کہ مسلمانوں میں سے جدید العہد یاکفار میں سے بعض لوگ چونکہ خود اُن کے اندر یہ نقائص پائے جاتے ہیں اِس لئے وہ اِن نقائص کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنے میں حرج نہیں سمجھتے.تمہیں اِ ن باتوں سے بچنا چاہیے اور رسول کے متعلق مقامِ ادب پر کھڑا ہونا چاہیے.احادیث کی روایتوں کو نظر انداز کر نے کی صورت میں عَبَسَ وَ تَوَلّٰی کے معنے اگر روایتوں کو نظر انداز کر دیا جائے تب تو آسانی سے اِن آیات کے یہ معنے کئے جا سکتے ہیں کہ عَبَسَ وَ تَوَلّٰۤى کافر کی نسبت ہے اور مراد یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب رئوساء مشرکین بیٹھے ہوئے تھے ایک اندھا آیا اور اُس نے کچھ سِیکھنا چاہا اس پر ایک کافر سردار نے عبوست کا اظہار کیا.اور مُنہ پھیرلیا.گویا اِس امر کو کہ آپؐ کے پاس ایک اندھا سیکھنے آیا ہے ایک حقیر امر سمجھا اور اس پر حقارت کا اظہار مُنہ پھیر لینے سے کیا.اس پر فرماتا ہے اے عبوست اور تولّٰی کرنے والے! تجھے کیا معلوم ہے یہ شخص تو تزکیہ حاصل کرے گا یا نصیحت سُنے گا اور اُس سے فائدہ اٹھائے گا اور بطور دوست اور شاگرد ایسا ہی آدمی مفید ہوتا ہے اور عقلمند ایسے ہی انسان کی عزّت کرتے ہیں.باقی رہا مالدار اور ظاہری ترقی یافتہ سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غرباء کے آنے پر ناک بھوں چڑھانے والے تُو تو ایسے ہی آدمی کی طرف لپکتا ہے اور اُسی کی طرف توجہ کرتا ہے.اور تجھے اس کا کوئی احساس نہیں ہوتا کہ وہ پاک ہوتا ہے یا بدکار ہوتا ہے تجھے تو اس سے غرض ہے کہ وہ مالدار اور دولتمند ہو پھر کسی اور شے کی پروا نہیں.اور دوسرا شخص جو تیری طرف دوڑتا آتاہے (یعنی سوالی یا حاجتمند) اور اس کا دل ڈر رہا ہوتا ہے کہ یہ بڑا آدمی ہے میری بات بھی سُنتا ہے یا نہیں.تُو نہ اس کو اپنی عنایت کا امیدوار سمجھ کر اس کی قدر کرتا ہے اور نہ اُس کی مسکینی اور دھڑکتے ہوئے دل کا
Page 246
خیال کرتا ہے اور اُسے کہہ دیتا ہے ہمیں فرصت نہیں اور سمجھتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اندھوں اور اپاہجوں کی طرف توجہ کرنا اُ س کے ادنیٰ ہونے کی علامت ہے اور تیرا مالداروں کی صحبت کا متلاشی ہونا تیرے بڑے ہونے کی علامت ہے.مگر یہ امر درست نہیں کیونکہ قابلِ توجہ وہی ہے جس کی اصلاح اور پاکیزگی کی امید کی جائے.پس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل مستحسن ہے اور تیرا ناک بُھوں چڑھانا ناواجب ہے.اِن آیات میں بتایا ہے کہ اسلام کے آئندہ سپاہی امراء سے نہیں چُنے جائیں گے بلکہ اللہ تعالیٰ اُن کا انتخاب اُن ارواحِ طیّبہ سے کرے گا جو صداقت کو ماننے اور پاکیزگی کو حاصل کرنے کی تڑپ رکھتی ہیں.گویا اَلنَّازِعَات اَلنَّاشِطَات وغیرہ ارواح جن کا اُوپر ذکر ہوا تھا ان کی نسبت بتاتا ہے کہ اُن کی جستجو مالداروں اور رئوساء میں نہ کرو اللہ تعالیٰ کے علم میں وہ کہیں اور دبکی بیٹھی ہیں اللہ تعالیٰ ہی اُن کو چُنے گا.كَلَّاۤ اِنَّهَا تَذْكِرَةٌۚ۰۰۱۲فَمَنْ شَآءَ ذَكَرَهٗۘ۰۰۱۳ (ایسا) ہر گز نہیں (یہ سب الزامات غلط ہیں) یقیناً یہ (قرآن)تو ایک نصیحت ہے پس جو چاہے اسے اپنے ذہن میں مستحضر کر لے.تفسیر.کَلَّا اِنَّھَا تَذْکِرَۃٌ میں ابن ام مکتوم کے متعلق آنحضرت ؐ پر اعتراض کرنے والوں کا جواب اُن معنوں کے لحاظ سے جن کو اوپر بیان کیا جا چکا ہے کَلَّآ کا لفظ اس کمزور انسان کے متعلق سمجھا جائے گا جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق شبہ کیا اور اپنے دل میں بعض ایسے وساوس کو آنے دیا جو اعلیٰ درجہ کے ایمان کے خلاف تھے.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کَلَّآ ہر گز یوں بات نہیں جس طرح تم خیال کرتے ہو اِنَّھَا تَذْکِرَۃٌ یہ چیز جو ہماری طرف سے آئی ہے یہ تو ایک نصیحت کے طور پر ہے یعنی قرآن کریم خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک نصیحت نامہ کے طور پر نازل ہواہے اور اُس کے نزول سے ہماری غرض یہ ہے کہ دُنیا کے تمام لوگ ہدایت پائیں پس جبکہ اس کتاب کی غرض لوگوں کو ہدایت کے راستہ پر قائم کرنا ہے تو بنی نوع انسان میں سے جس شخص کے قلب کو بھی اِس ہدایت سے مناسبت ہو گی وہ اس کو ضرور قبول کرے گا کیونکہ جب یہ چیز اُسی زمین میں پنپ سکتی ہے جو اس کے مناسب حال ہو تو وہ لوگ جو اُس سے مناسبت نہیں رکھتے ہوں گے وہ اس کی طرف آئیں گے ہی نہیں.اور جو لوگ اُس سے مناسبت رکھتے ہوں گے وہ خود بخود آ جائیں گے اُن کو چننے اور انتخاب کرنے کا سوال ہی کہاں پیدا ہو سکتا ہے.مَیں نے جیسا کہ شروع میں بیان کیا تھا سورۂ نازعات کے متعلق یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ یہ نَازِعَات اور
Page 247
نَاشِطَات بننے والی روحیں آئیں گی کہاں سے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے دل میں یہ سوال کیوں پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں کہاں سے آئیں گے جب ہم نے خود ان لوگوں کو چُننا ہے او ر جب ان کا انتخاب ہمارے ہاتھوں میں ہے تو تمہیں اس کے متعلق کسی فکر کی ضرورت نہیں.ہم جانتے ہیں کہ نَازِعَات اور نَاشِطَات بننے والی قابلیتوں کے حامل کون کون لوگ ہیں اور آیا وہ اُمراء میں ہیں یا غُرباء میں یا اُمراء اور غُرباء دونوں میں ہیں.ہم اُن کے ذاتی اوصاف سے آگاہ ہیں.ہمیں اُن کی مخفی قابلیتوںکا علم ہے اور ہم جانتے ہیں کہ کسی میں کیا کیا خوبیاں پائی جاتی ہیں.اس لئے ہم خود ان عظیم الشان امور کی سرانجام دہی کے لئے قابلیّتیں رکھنے والے نفوس کو کھینچ کھینچ کر لائیں گے قطع نظر اِس کے کہ ایسے نفوس اُمراء میں ہوں یا غرباء میں.چنانچہ دیکھ لو حضرت عثمانؓ اسلام میں داخل ہوئے جو مکّہ کے مالدار خاندان میں سے تھے اور طلحہؓ اور زبیرؓ بھی اسلام میں داخل ہوئے جو چوٹی کے رئیس خاندانوں میں سے تھے گو اُس وقت قوم کے منتخب لیڈر نہ تھے.فرق صرف یہ تھا کہ حضرت طلحہؓ اور حضرت زبیرؓ دولت اپنے ساتھ نہیں لائے لیکن حضرت عثمان اپنے ساتھ دولت بھی لائے.گویا امراء اور معزّز خاندانوں میں سے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے مناسب حال پایا اُن کو کھینچ لایا اور جن کو غرباء میں سے اسلام کے مناسب حال دیکھا اُن کو غرباء میں سے کھینچ لایا.اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے ہماری جماعت کے ایک دوست تھے شیخ غلام احمد صاحب مرحوم اُن کو اپنے متعلق تصوّف میں دخل رکھنے کا خاص خیال تھا اور وہ سمجھتے تھے کہ تصوّف کے متعلق جو اُن کانظریہ ہے وہی سب دُنیا کا ہونا چاہیے.ایک دفعہ وہ مجھ سے ملے اور کہنے لگے بتائیے آپ کو غریب اچھے لگتے ہیں یا امیر اچھے لگتے ہیں.میں نے پہلے تو اُن کو ٹالنا چاہا مگر جب بار بار اور اصرار کے ساتھ انہوں نے یہ سوال کیا تو میں نے اُنہیں کہا کہ مجھے نہ امیر اچھے لگتے ہیں نہ غریب اچھے لگتے ہیں نہ امیر بُرے لگتے ہیں نہ غریب بُرے لگتے ہیں.میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ جہاں تک خدا تعالیٰ کے کام کا تعلق ہے اس کو سرانجام دینے کے لئے وہ میرے ساتھ کسی امیر کو وابستہ کرتا ہے یا کسی غریب کو وابستہ کرتا ہے.اگر میرے کام کے لئے وہ ایک غریب کو چُنتا ہے تو وہی مجھے اچھا لگتا ہے اور اگر میرے کام کے لئے وہ ایک امیر کو چُنتا ہے تو وہی مجھے اچھا لگتا ہے میں تو اللہ تعالیٰ کے اشارہ کی طرف نگاہ رکھتا ہوں کہ وہ کس آدمی کو کام کے لئے میرے ساتھ وابستہ کر رہا ہے.اگر امیر ہوتو مجھے اس امیر سے محبت ہو جاتی ہے اور اگر غریب ہو تو مُجھے اُس غریب سے محبت ہو جاتی ہے.تو اللہ تعالیٰ کی یہ سُنّت ہے کہ وہ اپنے کام کے لئے امیروں کو بھی چُنتا ہے اور غریبوں کو بھی چُنتا ہے مگر اکثر وہ غریبوں میں سے چُنتا ہے اور اگر کوئی امیر چُنا جاتا ہے تو اس وجہ سے نہیں کہ خاندانی لحاظ سے
Page 248
اللہ تعالیٰ اس کو آگے لانا پسند کرتا ہے بلکہ اس وجہ سے کہ ذاتی قابلیتوں کے لحاظ سے و ہ اس بات کا مستحق ہوتا ہے کہ اُسے آگے لایا جائے مگر چونکہ خاندانی عظمت کا جوہر بھی اُس کے ساتھ ہوتا ہے اس لئے نبی کی جماعت میں وہ عزت پا جاتا ہے.یہ مضمون ہےجو اللہ تعالیٰ اس آیت میں بیان فرما رہا ہے کہ کَلَّآ اِنَّھَا تَذْکِرَۃٌ.یہ قرآن تو ایک نصیحت کی کتا ب ہے جو چاہے اِسے پڑھے اور جو چاہے اس سے فائدہ اٹھا لے.اس میں نبی کا کوئی واسطہ نہیں.خدا تعالیٰ نے مختلف لوگوںکی طبائع اس کے مطابق بنا دی ہیں اور وہ آہستہ آہستہ اس سے فائدہ اٹھاتے چلے جائیں گے ان کے راستہ میں کوئی چیز روک نہیں بن سکتی اگر امیر کو اس کے ساتھ قلبی مناسبت ہے تو اس امیر کو روکا نہیں جا سکتا اور اگر ایک غریب کو اس کے ساتھ قلبی مناسبت ہے تو اُس غریب کو روکا نہیںجا سکتا.فَمَنْ شَآءَ ذَكَرَهٗ یہ خیال کر لینا کہ دین صرف غریبوں کے لئے ہی ہے کسی طرح درست نہیں ہو سکتا.دین غریبوں کے لئے بھی ہے اور دین امیروں کے لئے بھی ہے جو چاہے خدا تعالیٰ کے دین میں داخل ہو کر فائدہ اٹھا لے اور اللہ تعالیٰ کے قرب میں بڑھ جائے ہم نے کسی کو روکا ہوا نہیں.یہی فقرہ ہے جو میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہا اور جس پر آج کل خاص طور پر زور پڑا ہوا ہے میں نے کہاکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب کے راستوں کو محدود نہیں کیا.اُس نے اپنے فرشتوں کو اعلیٰ درجہ کے روحانی مدارج پر اس لئے نہیں کھڑا کر دیا کہ اب کسی کو آگے مت بڑھنے دو.خدا تعالیٰ کے قرب کے راستے کھلے ہیں اور کھلے رہیں گے یہاں تک کہ اگر کوئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کے قرب میںبڑھنا چاہے تو وہ بڑھ سکتا ہے.اس کا مطلب یہی تھا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی روک نہیں اگر کوئی بڑھ سکتا ہے تو بڑھ کر دکھا دے.مگر جب کسی نے اب تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نہیں دکھایا اور نہ آئندہ دکھا سکتا ہے تو گو حقیقت یہی ہو گی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہیں مگر کہا یہی جائے گا کہ خدا تعالیٰ نے جبراً آپ کو اس مقام پر نہیں پہنچایا اور نہ اُس نے زبردستی طور پر دوسروں کو بڑھنے سے روکا.خدا تعالیٰ کے قرب کے راستے کھلے ہیں اور اگر کوئی شخص بڑھنا چاہے تو بڑھ سکتا ہے.یہی مضمون اللہ تعالیٰ نے اس جگہ بیان فرمایا ہے کہ فَمَنْ شَآءَ ذَكَرَهٗ ہماری طرف سے کوئی روک نہیں قرآن تو ساری دنیا کے لئے ہے.امیر کے لئے بھی ہے اور غریب کے لئے بھی ہے.عالم کے لئے بھی ہے اور جاہل کے لئے بھی ہے.کالے کے لئے بھی ہے اور گورے کے لئے بھی ہے.مشرقی کے لئے بھی ہے اور مغربی کے لئے بھی ہے.جو چاہے اس سے فائدہ اٹھا لے.اِنَّھَا تَذْکِرَۃٌ میں ھا کی ضمیر کا مرجع اِنَّھَا میں ھَا کی ضمیر ہدایت اور موعظت کی طرف جاتی ہے گویا اِنَّھَا
Page 249
تَذْکِرَۃٌ کے معنے یہ ہیں کہ اِنَّ الْھَدَایَۃَ الَّتِیْ جَآئَ تْ مِنَ اللّٰہِ تَذْکِرَۃٌ فَمَنْ شَآئَ ذَکَرَہٗ اَیِ الْقُرْاٰنَ.پس جو چاہے اس کلام سے جو ہم نے نازل کیا ہے فائدہ اٹھا لے.ھَا کی ضمیر دونوں طرف جا سکتی ہے ذِکْریٰ کی طرف بھی جس کا ذکر اوپرآچکا ہے اور قرآن کی طرف بھی.مگر اگلی آیات میں چونکہ خصوصیت سے قرآن کریم کا ذکر کیا گیا ہے اس لئے وہی مراد ہے اور ا س امر کو ظاہر کرنے کے لئے ایک جگہ مؤنث کی ضمیر یعنی ھَا کو استعمال کر دیا اور آگے ذَکَرَہٗ میں مذکّر کی استعمال کر کے بتا دیا کہ مراد قرآن کریم ہے ہاں اس کی صفت تذکیر کی طرف خاص طور پر توجہ دلانا مقصود ہے اس لئے اس کی طرف مؤنث کی ضمیر پھیری گئی ہے.ایک نیا نکتہ.سورۃ عبس کی پہلی آیت کے ایک اور لطیف معنے آیات مذکورۃ الصدر کے ایک اور لطیف معنے بھی ہو سکتے ہیں.اور انہی کے مطابق میں نے ترجمہ کیا ہے اور وُہ معنے یوں ہیں کہ اس جگہ کلام طنزیہ ہے جیسے کہ ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذُقْ اِنَّکَ اَنْتَ الْعَزِیْزُ الْکَرِیْمُ (الدخان :۵۰) یعنی یہ جہنم کا کھانا کھا تُو تو بہت ہی طاقتو ر اور معزز تھا مطلب یہ کہ تو اپنے آپ کو طاقتور اور معزز کہا کرتاتھا حالانکہ تو نہ طاقتور تھا اور نہ معزز تھا یہ سب تیرے نفس کا فریب تھا اگر تُو اپنے خیال کے مطابق ہوتا تو آج تجھ کو جہنم کی ذلیل غذائیں کیوں کھانی پڑتیں.صاحب کشاف کہتے ہیں کہ یہ آیت ھزء اور تہکم کی قسم سے ہے(تفسیر کشاف الجزء الرابع صفحہ ۲۸۲ زیر آیت ذق انک انت...) یعنی دشمن کے قول کی بظاہر تصدیق کی گئی ہے لیکن اصل میں اس کی تردید مراد ہے اور مطلب یہ ہے کہ تمہارا یہ قول بالکل خلاف عقل ہے.دوسری زبانوں میں بھی یہ کلام طنز استعمال ہوتا ہے چنانچہ اُردو میں بھی اگر کوئی شخص کسی کا دوست ہو اور ہمیشہ اس کی خیر خواہی کرتا رہا ہو اور وہ دوسرا شخص کسی موقعہ پر اس کی طرف کوئی ایسی بات منسوب کر دے جو خیر خواہی کے خلاف ہو تو وہ دوست اُسے جواب میں کہتا ہے ’’ہاں ہاں کیوں نہیں میں تمہارا دشمن جو ہوا.‘‘ اور مراد اس کی یہ ہوتی ہے کہ مَیں تو تمہارا دوست ہوں اور ہمیشہ تمہاری خیر خواہی کرتا رہا ہوں تم ایسا الزام مجھ پر کس طرح لگا سکتے ہو.غرض مدّنظر تو تردید ہوتی ہے لیکن ظاہر میں انسان اس قول کی تائید کرتا ہے.ذُقْ اِنَّکَ اَنْتَ الْعَزِیْزُ الْکَرِیْمُ(الدخان :۵۰) میں بھی یہی طریق کلام استعمال کیا گیا ہے.دشمن کہا کرتا تھا کہ میں عزیز وکریم ہوں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذباللہ ذلیل ہیں.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن ہم اُسے دوزخ میں ڈالیں گے اور اُسے کہیں گے لو یہ عذاب چکھو اس لئے کہ تم عزیز و کریم ہو اور مطلب اس کا یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو عزیز وکریم کہنے میں جھوٹے تھے.اگر تم عزیز وکریم ہوتے تو یہ عذاب تمہیں کیوں دیا جاتا.اسی رنگ کا کلام میرے نزدیک اس سورۃ میں بھی ہے.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ ایک اندھا آیا.اُس نے
Page 250
ایک بےموقعہ بات کی اور آپ کے چہرے پر نا پسندیدگی کے آثار ظاہر ہوئے.لیکن آپ نے اپنی ناپسندیدگی کو دبانے کے لئے اس کی طرف سے مُنہ پھیر لیا.کفار تو مومنوں میںپھوٹ ڈلوانے کی ہمیشہ کوشش کیا ہی کرتے ہیں.جب کفار کو اس واقعہ کا علم ہوا اور کیوں نہ معلوم ہوتا کہ خود کفار ہی کی موجودگی میں یہ واقعہ ہوا تھا تو کفار نے اسلام کو نقصان پہنچانے کے لئے اِس واقعہ سے ناجائز فائدہ اٹھایا اور یہ مشہور کرنا شروع کیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک غریب ساتھی کی بڑی ہتک کی ہے صرف اس لئے کہ وہ غریب تھا جب آپؐ کے پاس شرفاء مکہ بیٹھے تھے اس کے آنے پر آپؐ ناراض ہو گئے.اور اس ذریعہ سے مسلمانوں کے دلوں میں تذبذب اور شبہ پیدا کرنے کی کوشش کی.آنحضرت ؐ کے اخلاق کو پیش کر کے آنحضرت ؐ پر ابن ام مکتوم کے متعلق اعتراض کر نے والوں کا منہ توڑ جواب اللہ تعالیٰ اُن کے اِس اعتراض کی کمزوری اور لغویّت ظاہر کرنے کے لئے ھزء اور تحکم کے رنگ میں اس اعتراض کا ذکر کرتا ہے اور فرماتا ہے عَبَسَ وَ تَوَلّٰۤى.اَنْ جَآءَهُ الْاَعْمٰى ہمارے رسول نے تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا صرف اتنی سی بات پر کہ ابنِ اُم مکتوم اُس کے پاس آیا.اور مطلب یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ظاہر ہیں اور دوست ودشمن اُن سے واقف ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہی غر باء کے ساتھ رہتی تھی اور غرباء کی جماعت ہی آپؐ کے اردگرد بیٹھتی تھی جو شخص غلاموں کی آزادی اور غریبوں، بیوائوں، یتیموں اور مسکینوں کی ترقی کے لئے رات دن مشغول رہتا ہو اس پر یہ الزام لگانا کہ صرف اس وجہ سے کہ ایک اندھا اس کے پاس آیا تھا اُس نے تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا.کوئی عقلمند اِس کو تسلیم نہیں کر سکتا.پس یہ الزام خود ہی اپنی ذات میں تردید کر رہا ہے.جیسے کہتے ہیں آفتاب آمد دلیلِ آفتاب.سورج کا نِکلنا ہی سورج ہونے کی دلیل ہوتی ہے.محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اِس امر کا منسوب کرنا ہی اِس الزام کا کافی جواب ہے کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں.پھر وَ مَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّهٗ يَزَّكّٰۤى اَوْ یَذَّکَّرُ فَتَنْفَعَہُ الذِّکْرٰی کہہ کر اس تردید کو دلیل عقلی سے بھی مکمل کر دیااور فرمایا کہ اندھے یا سوجاکھے کا سوال نہیں بلکہ سوال یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا کیا علم ہو سکتا تھا کہ کون سا شخص ہدایت پائے گا اور کون سا نہیں.کون ہدایت پر قائم رہے گا اور کون پھسل جائے گا.محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ظاہری شریعت کے پابند ہیں اور غیب کے علم میں دخل اندازی پسند نہیں کرتے.غیب کا علم خدا کے پاس ہے اور وہی جانتا ہے کہ جو لوگ آج کافر نظر آتے ہیں وہ مرتے وقت کیا ہوں گے اور جو لوگ آج مومن نظر آتے ہیں وہ مرتے وقت کیا ہوں گے.ہماری شریعت کا ظاہری حکم یہی ہے کہ جو شخص ہم سے بات کر رہا ہو ہم پہلے اُس کی
Page 251
طرف توجہ کریں اور بعد میں آنیوالا اپنے موقع کا انتظار کرے.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کے اس حکم پر عمل کیا اور خدا کے حکم کو پورا کر دیا.غیب کا آپؐ کو علم نہیں تھا کہ آپؐ کہہ سکتے کہ کس کو تبلیغ کرنا وقت کو ضائع کرنا ہے اور کس کو تبلیغ کرنا وقت کو صحیح طور پر استعمال کرنا ہے ایک وقت وہ تھا کہ بلالؓ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے لئے تکلیفیں اٹھا رہا تھا.جلتی ریت پر اُس کو لٹایا جاتا.کُھردرے پتھروں پر اس کو گھسیٹا جاتا اور نوجوان اُس کے ننگے سینہ پر چڑھ چڑھ کر کُودتے تا کہ اُسے اسلام سے پھرا دیں (اسد الغابۃ بلال بن رباح)اور عمرؓ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مارنے کے لئے تلوار لئے پھرتے تھے(السیرۃ النبویۃ لابن ہشام اسلام عمر بن الخطاب) لیکن بعد کے واقعات نے کیابتایا.بے شک بلالؓ کا انجام بہت ہی اچھا ہوا مگر جس مقام کو عمرؓ پہنچے بلالؓ تو نہیں پہنچے.پس محض اس لئے کہ کوئی شخص اُس وقت کافر تھا اور کوئی دوسرا شخص اُس وقت مسلمان تھا اُس کو بناء قرار دیتے ہوئے شریعت کا ظاہری حکم محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کِس طرح توڑ سکتے تھے.آپؐ کو کیا معلوم تھا کہ وہ ظاہر میں کافر نظر آنے والے لوگ آئندہ کیا بننے والے تھے.چنانچہ بعض روایات میں آتا ہے کہ اُن میںحضرت عباسؓ بھی تھے(تفسیر فتح البیان الجزء الخامس عشر صفحہ ۷۶).اور ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ ابنِ اُمّ مکتوم عباسؓ کے درجہ کو نہیں پہنچے.حضرت عباسؓ سے جو شوکت اسلام کو پہنچی اور خلفائِ اسلام ان کی زندگی میں جس طرح اُن کا مشورہ لیتے اور اس پر عمل کرتے تھے وہ اُن کے عالی مقام پر شاہد ہے.پس مَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّهٗ يَزَّكّٰۤى.اَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرٰى میں خدا تعالیٰ نے عام طریق استدلال سے بھی اِس اعتراض کو ردّ کر دیا پھر اَمَّا مَنِ اسْتَغْنٰى.فَاَنْتَ لَهٗ تَصَدّٰى کہہ کر اسی قسم کے تہکم والے کلام کی طرف دوبارہ رجوع کیا اور کفار کا یہ بقیہ اعتراض دُہرایا کہ لو جی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ نہیں کرتا اُس کی طرف بوجہ اُس کے عالی مرتبہ ہونے کے آپؐ بڑی توجہ کرتے ہیں.اِس اعتراض کو بھی ھزء اور تہکم کے طور پر اِس طرح دُہرایا گیا ہے گویا اِس اعتراض کی صِحّت کو قبول کر لیا گیا ہے بعینہٖ اسی طرح جس طرح وہ شخص جس کا انصاف ظاہر ہو معترض کے جواب میں کہتا ہے.ہاں ہاں مَیں تو ظالم ہوں ہی لیکن اس اعتراض کے دُہرانے کے معنے یہ ہوتے ہیں کہ مرے وجود کی طرف اِس اعتراض کا منسوب ہونا ہی اِس کے غلط ہونے کا ثبوت ہے.اِس جگہ اِس اعتراض کے نقل کرنے سے بھی یہی مراد ہے کہ ایسا ہر گز نہیں.چنانچہ پہلے اعتراض کی طرح یہاں بھی بعد میں اس اعتراض کے ردّ کرنے کی عقلی دلیل بیان فرما دی اور فرمایا کہ وَ مَا عَلَيْكَ اَلَّا يَزَّكّٰى یہ اعتراض ہی بالبداہت غلط ہے.تیرے متعلق یہ کہنا خلافِ عقل بات ہے.اگر یہ لوگ سمجھ سے کام لیں تو ان کومعلوم ہو سکتا ہے کہ اُن کفار کا جو مجلس میں بیٹھے تھے ہدایت پانا یا نہ پانا نہ تیرے اختیار میں ہے نہ تیرے سپُرد ہے.گویا پہلی
Page 252
آیات میں تو یہ بتایا گیا تھا کہ ابنِ اُم مکتوم کا ہدایت پر مرنا تیرے علم کی بات نہیں اور اِ س آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ اِن کفار کے ہدایت نہ پانے پر تجھ سے کوئی باز پُرس نہ ہونی تھی پھر کس ذاتی غرض سے تُو نے ابن اُم مکتوم کی طرف توجہ نہ کی اور کس فائدہ کی وجہ سے تُو نے اُن کفار کی طرف توجہ کی نہ تو ابن اُم مکتوم کی طرف توجہ نہ کرنے میں تیرا کوئی فائدہ تھا.اور نہ اُن کفّار کی طرف توجہ کرنے میں تیرا کوئی فائدہ تھا پس اِن واقعات کی موجودگی میں ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ اس واقعہ کی وجہ کچھ اور ہی تھی.(وہ وجہ وہی تھی جو ہم اوپر بیان کر چکے ہیں یعنی شریعت کے ظاہری احکام کی پابندی).اس کے بعد فرماتا ہے وَ اَمَّا مَنْ جَآءَكَ يَسْعٰى.وَ هُوَ يَخْشٰى.فَاَنْتَ عَنْهُ تَلَهّٰى یہ بھی کفار کا ہی قول ہے اور بطور ھزء و تحکم اِسے یوں بیان کیا گیا ہے گویاواقعہ ہے اور مطلب یہ ہے کہ کفار یہ بھی کہتے ہیں کہ جو شخص تیری طرف دَوڑتا ہوا آتا ہے اور جو خدا سے ڈرتا ہے اس کی طرف سے محمد (صلے اللہ علیہ وسلم ) بے اعتنائی کرتے ہیں چونکہ یہ ھزء اور تحکم کے طور پر عبارت ہے اس لئے اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے.عَبَسَ وَ تَوَلّٰۤىکے نئے کئے ہوئے معنے کی تائیدكَلَّاۤ اِنَّهَا تَذْكِرَةٌسے میرے اِن معنوں کا قطعی اور یقینی ثبوت اِس بات سے مِلتا ہے کہ اِن آیات کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کَلَّا اِنَّھَا تَذْکِرَۃٌ اور کَلَّا کے معنے ہوتے ہیں جو پہلی بات کہی گئی ہے وہ غلط ہے اب یہ صاف بات ہے کہ پہلی بات جو کہی گئی ہے وہ وہی اعتراض ہیں جو دشمنوں کی طرف سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کئے گئے ہیں یعنی آپؐ نے ایک اندھے کے معاملہ میں بداخلاقی سے کام لیا اور بعض دولت مندوں کی طرف زیادہ توجہ کی.کیا یہ عجیب بات نہیں کہ خدا تعالیٰ جس بات کی تردید کرے ہم اس کی تصدیق کریں.کَلَّا کے لفظ نے بتا دیا ہے کہ یہ سب اعتراضات غلط ہیں.پس جتنی باتیں پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض والی بیان ہوئی ہیں وہ بطور ھزء اور تہکم کے بیان کی گئی ہیں اور ظاہر الفاظ تو تصدیق کے ہیں لیکن اصل مراد انکار ہے جیسا کہ اس طریقِ کلام کا قاعدہ ہے.کَلَّا کے معنے یہی ہوا کرتے ہیں کہ اس سے پہلے جو بات مذکور ہو اس کا اِس کلام سے سختی سے ردّ کیا جاتا ہے.چنانچہ کلیات ابی البقاء میں لکھا ہے قَالَ عَمْرُوبْنُ عَبْدِ اللّٰہِ اِذَا سَمِعْتَ اللّٰہَ یَقُوْلُ کَلَّا فَاِنَّمَا یَقُوْلُ کَذَبْتَ یعنی عمرو بن عبداللہ فرماتے ہیں جب تم خدا کے کلام میں کَلَّا کا لفظ پڑھو تو سمجھ لو کہ اُس کے معنے یہ ہیں کہ پہلی باتوں کا کہنے والا جھوٹا ہے.پس كَلَّاۤ اِنَّهَا تَذْكِرَةٌ کے معنے یہ ہوئے کہ پہلے جو اعتراضات بیان کئے گئے ہیں وہ جھوٹے ہیں اور ان کے جھوٹے ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ قرآن کریم ایک نصیحت کی کتاب ہے کافر کو سُنانا بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
Page 253
کا فرض ہے اور مومن کو سُنانا بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض ہے.پس اگر آپ قرآن شریف کفار کو سُنا رہے تھے تو ایک مومن کو یہ حق حاصل نہیں تھا کہ وہ درمیان میں بولتا.اور اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کا جواب نہیںدیا تو بالکل ٹھیک کیا.کَلَّا کا استعمال کلام عرب میں مغنی اللبیب میں کَلَّا کے متعلق بحث کرتے ہوئے لکھا ہے عِنْدَ سِیْبَوَیْہِ وَ الْخَلِیْلِ وَ المُبَرِّ دِ وَ الزَّجَاجِ وَاَکْثَرِ الْبَصْرِیِّیْنَ حَرْفٌ مَعْنَاہُ الرَّدْعُ وَالزَّجْرُ لَا مَعْنَی لَھَا عِنْدَھُمْ اِلَّا ذَالِکَ حَتّٰی اِنَّھُمْ یُجِیْزُوْنَ اَبَدًا اَلْوَقْفُ عَلَیْھَا وَالْاِبْتِدَاءُ بِمَا بَعْدَ ھَا وَحَتّٰی قَالَ جَمَاعَۃٌ مِّنْھُمْ مَتٰی سَمِعْتَ کَلَّا فِیْ سُوْرَۃٍ فَاحْکُمْ بِاَنَّھَا مَکِّیَۃٌ لِاَنَّ فِیْھَا مَعْنَی التَّھدِیْدِ وَالْوَعِیْدِ وَاَکْثَرُ مَا نَزَلَ ذَالِکَ بِمَکَّۃَ لِاَنَّ اَکْثَرَ الْعَتُوِّ کَانَ بِھَا.یعنی سیبویہ اور خلیل اور مبرّداور زجاج اور اکثر بصری کہتے ہیں کہ اس کے معنے زجر اور تردید کے ہوتے ہیں.اُن لوگوں کے نزدیک اس کے سوا کَلَّا کے اور کوئی معنے ہی نہیں ہیں یہاں تک کہ وہ لوگ اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ ہمیشہ کَلَّا کے لفظ پر وقف کر لینا اور مابعد کے فقرہ کو ایک نیا جملہ فرض کر لینا چاہیے.اور ان میں سے ایک جماعت تو یہاں تک کہتی ہے کہ جب کسی سورۃ میں کَلَّا کا لفظ آئے تو سمجھ لو کہ وہ مکّی ہے کیونکہ اس لفظ کے معنوں میں ڈرانے اور دھمکی دینے کا مفہوم پایا جاتا ہے اور زیادہ تر یہ لفظ مکّی سورتوں میں اترا ہے کیونکہ اکثر شرارتیں اور زیادتیاں مکّہ میں ہی ہوا کرتی تھیں اس پر صاحبِ مغنی نے بے شک اعتراض کیا ہے کہ قرآن شریف میں جو یہ آتا ہے کہ يٰۤاَيُّهَا الْاِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ.الَّذِيْ خَلَقَكَ فَسَوّٰىكَ فَعَدَلَكَ.فِيْۤ اَيِّ صُوْرَةٍ مَّا شَآءَ رَكَّبَكَ.كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُوْنَ بِالدِّيْنِ (الانقطار :۷ تا ۱۰) اس میں کوئی تہدید یا وعید نظر نہیں آتا مگر یہ اعتراض بالبداہت باطل ہے اس لئے کہ قرآن کریم نے خود ہی بتا دیا ہے کہکَلَّا کے لفظ سے پہلے اعتراض ہی مراد تھا کیونکہ فرماتا ہے بَلْ تُكَذِّبُوْنَ بِالدِّيْنِ تم جزاء سزا کو جھٹلاتے ہو جس سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلی آیات میں ان لوگوں کا ردّ تھا جو جزاءسزاء کے منکر ہیں پس جب ایسے لوگوں کا ذکر تھا جو جزاءسزاء کے منکر تھے اور انہی کی تردید کی جار ہی تھی.تو کَلَّا میں وعید اور تہدید مراد نہیں ہو گی تو کیا پیار مراد ہو گا؟ غرض بڑے بڑے نحویوں اور ادیبوں کی نگاہ میں کَلَّا کا لفظ منکرین اور مخالفین کے لئے استعمال ہوتا ہے اور تہدید اور وعید اس میں شامل ہوتی ہے.پس كَلَّاۤ اِنَّهَا تَذْكِرَةٌ سے معلوم ہوا کہ پہلے اقوال خدا تعالیٰ کے مصدقہ نہیں بلکہ منکروں اور دشمنانِ اسلام کے ہیں جن کو ردّ کیا گیا ہے تبھی تو ہر اعتراض کے بعد اللہ تعالیٰ اُن کی تردید کرتا ہے اگر واقعہ اسی طرح ہوتا اور یہ الزام وہ ہوتے جن کی خدا تعالیٰ تصدیق کرتا ہے تو پھر ان آیات کے بعد کَلَّا کے استعمال
Page 254
کے کیا معنے تھے؟ پھر تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ یہ الزام بالکل سچے ہیں.پس پہلے الزام بیان کرنا اور پھر کَلَّا کہنا بتاتا ہے کہ یہ الزام دشمنوں کی طرف سے غلط طور پر لگائے گئے تھے.اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں محض ھزء اور تہکم کے رنگ میں اُن کا ذکر کیا ہے اور مطلب یہ ہے کہ ہمارے رسول کو یوں کہا جاتا ہے.مگر یہ بالکل جھوٹ ہے وہ ایسا نہیں بلکہ ان تمام الزامات سے پاک ہے.فِيْ صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍۙ۰۰۱۴مَّرْفُوْعَةٍ مُّطَهَّرَةٍۭۙ۰۰۱۵بِاَيْدِيْ (وہ قرآن ایسے) صحیفوں میں ہے (جو) عزت والے ہیں بلند شان (اور) پاک ہیں (لکھنے والوں اور دُور دُور) سَفَرَةٍۙ۰۰۱۶كِرَامٍۭ بَرَرَةٍؕ۰۰۱۷ سفر کرنے والوں کے ہاتھوں میں (ہیں) (ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں جو) معزز ہیں اور اعلیٰ درجہ کے نیکو کار ہیں.حَل لُغَات.مُکَرَّمَۃٌ مُکَرَّمَۃٌ کَرَّمَ سے ہے اور کَرَّمَ کے معنے ہوتے ہیں عَظَّمَ وَنَزَّہٗ اس کی بڑائی بیان کی اور اس کو عیوب سے منزّہ قرار دیا (اقرب) اور مُکَرَّمَۃٌ کے معنے ہوئے مُعَظَّمَۃٌ وَمُنَزَّھَۃٌ عَنْ کُلِّ خَطَائٍ وَنَقْصٍ یعنی وہ جن کی عظمت بیان کی جاتی ہے اور جن کو تمام نقائص خرابیوں اور عیوب سے مبرّا قرار دیا جاتا ہے.مَرْفُوْعَۃٌ مَرْفُوْعَۃٌ رَفَعَ سے ہے اور رَفَعَہُ (رَفْعًا) کے معنے ہوتے ہیں ضِدُّ وَضَعَہٗ اس کو اوپر کیا.بلند کیا.اور جب رَفَعَ اِلَی السُّلْطَانِ (رُفْعَانًا) کہیں تو معنے ہوں گے قَرَّبَہٗ کہ اس کو بادشاہ کا مقرب بنا دیا (اقرب) مُطَھَّرَۃٌ مُطَھَّرَۃٌ طَھَرَ سے ہے اور طَھَّرَہٗ کے معنے ہوتے ہیں جَعَلَہٗ طَاھِرًا.اُس کو پاک قرار دیا (اقرب) سَفَرَۃٌ.سَفَرَۃٌ اَلسَّافِرُ کی جمع ہے اور اس کے دو معنے ہوتے ہیں.ایک تو مسافر کے.ان معنوں میں اس کا کوئی فعل نہیں آتا.دوسرے معنی اس کے کاتب کے ہوتے ہیں (اقرب) کِرَامٌ.کِرَامٌ کَرِیْمٌ کی جمع ہے اور اس کے معنے معزز اور بزرگ لوگوں کے ہیں (اقرب) کبھی کبھی لفظ کَرِیْم ایسے سخی آدمی کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے جو لوگوں کو بہت ہی نفع پہنچائے اور کَرِیْمٌ اُس چیز کو بھی کہتے ہیں جو اپنی جنس میں سےبہترین ہو چنانچہ عرب کہتے ہیں اَلْکَرِیْمُ مِنْ کُلِّ قَوْمٍ اور ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ مَا یَجْمَعُ
Page 255
فَضَائِلَہُ کہ فلاں شخص ساری قوم میں سے کریم ہے یعنی ساری قوم کی خوبیاں اس میں پائی جاتی ہیں.اقرب کے مؤلف لکھتے ہیں ’’اَلْکَرِیْمُ مَنْ یُّوْصِلُ النَّفَعَ بِلَا عِوَضٍ فَالْکَرْم ھُوَ اِفَادَۃُ مَا یَنْبَغِیْ لَا لِعِوَضٍ‘‘ یعنی کریم ایسے شخص کو کہتے ہیں جو لوگوں کو نفع پہنچائے اور کسی سے معاوضہ کی خواہش نہ کرے (اقرب) پس کِرَامٌ کے معنے ہوں گے (۱)سخی (۲)بزرگ (۳)قوم میں سے بہترین (۴)ایسے لوگ جنہیں لوگوں کو بلا معاوضہ فائدہ پہنچانے کا جنون ہو.بَرَرَۃٌ بَرَرَۃٌ جمع ہے اَلْبَرُّ وَالْبَارُّ کی جو کہ بَرَّ سے اسم فاعل کا صیغہ ہے.اور بَرَّ وَالِدَہٗ کے معنے ہیں اَحْسَنَ الطَّاعَۃَ اِلَیْہِ وَرَفَقَ بِہٖ وَتَحَرّٰی مَحَابَّہٗ وَتَوَقّٰی مَکَارِہَہٗ (اقرب) کہ اُس نے اپنے والد کی پوری اطاعت کی اور اُس کے ساتھ نرمی سے پیش آیا اور اس کی خوشنودی کے ذرائع کو تلاش کیا اور اُن پر عمل کیا اور ہر ایک اُس بات سے بچا جو اُس کے والد کو ناراض کرے.تفسیر.فِيْ صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍمیں سور قرآن کی طرف اشارہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ قرآن ایسے صحیفوں میں ہے جو مُکَرَّمَۃٌ ہیں مَرْفُوْعَہ ہیں اور مَطَھَّرَہ ہیں.اس جگہ یہ امر یاد درکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے صُحْفُ کا لفظ استعمال فرمایا ہے جو جمع پر دلالت کرتا ہے صَحِیْفَہ کا لفظ استعمال نہیں کیا.اِس میں درحقیقت قرآن کریم کی سورتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی حکمت کے ماتحت الگ الگ ٹکڑوں میں نازل ہوئی ہیں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ان مختلف ٹکڑوں کو آپس میں یوں ہی جوڑ دیا گیا ہے کسی خاص حکمت کو مدنظر نہیں رکھا گیا مگر قرآن نہ صرف اُن کے علیحدہ علیحدہ نزول کو بلکہ اُن کے علیحدہ علیحدہ وجود کو تسلیم کرتا ہے اور ہر سورۃ کو ایک صحیفہ قرار دیتا ہے.گویا صُحُف کہہ کر اس امر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ قرآن کریم کی ہر سورۃ اپنی ذات میں ایک علیحدہ اور مستقل مضمون رکھتی ہے ورنہ وہ صحیفہ نہیں کہلا سکتی تھی.صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍکے الفاظ میں اس طرف اشارہ کہ قرآن مجید میں سب انبیاء کی تعلیم جمع کر دی گئی ہے دوسرےؔ صُحُف کہہ کر اُس امر کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے جس کا صُحُفِ اِبْرٰھِیْمَ وَمُوْسٰی (الاعلٰی:۲۰ ) کے الفاظ میں ذکر آتا ہے یعنی صُحُف کہہ کر اس حقیقت کو واضح کیا گیا ہے کہ صحف سابقہ کی تمام اعلیٰ درجہ کی اخلاقی اور روحانی تعلیموں کو جو انسانی فطرت کے مناسب حال تھیں اس قرآن میں جمع کر دیا گیا ہے گویا کتاب تو ایک ہی ہے مگر اس میں تمام انبیاء کے صحیفے جمع ہیں اسی لئے اُس کے لئے جمع کا لفظ لایا گیا اور صحیفہ کی بجائے صحف کہا گیا.حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کو بھی صحف اِسی لئے کہا گیا ہے کہ اُس میں آپؐ سے پہلے تمام انبیاء ؑ
Page 256
کی تعلیمیں جمع تھیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفہ کو بھی اسی لئے صحف کہا گیا کہ اُس میں نوح ؑ اور بعض دوسرے انبیاء ؑکے صحیفے جمع تھے.اور پھر قرآن کو بھی صحف کہا گیا کیونکہ قرآن وہ کتاب ہے جس نے آدمؑ سے لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک آنے والے تمام انبیاء کے صحف کو اپنے اندر جمع کر لیا اور کوئی تعلیم ایسی نہیں رہی جس کی بنی نوع انسان کو ضرورت ہو اور اس کا قرآن کریم میں ذکر نہ آتا ہو.گویا جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء کہا گیا اِن معنوں میں کہ آپؐ کے وجود میںتمام انبیاؑء سابقین جمع ہو گئے تھے اسی طرح آپؐ کی کتا ب کو صحف کہا گیا کیونکہ اس میں تمام انبیائِ سابقین کے صحیفوں کو جمع کر دیا گیا تھا درحقیقت کوئی نبی دُنیا میں ایسا نہیں آیا جو اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی صحیفہ نہ لایا ہو (مگر اس کے معنے یہ نہیں کہ وہ شریعت جدیدہ لایا یا احکام جدیدہ لایا.صحیفہ سے مراد ایک پیغامِ حقیقت ہے جو اُس وقت کے مناسب حال ہو) اِسی وجہ سے قرآن کریم میں صُحفِ ابراہیم کا ذکر ہے.حالانکہ وہ حامل شریعتِ جدیدہ نہ تھے.حضرت نوحؑ کے تابع تھے جیسا کہ قرآن کریم فرماتا ہے اِنَّ مِنْ شِیْعَتِہٖ لَاِ بْرٰھِیْمَ (الصافات:۸۴)آدم ؑ مبعوث ہوا تو وہ اپنے ساتھ پہلا صحیفہ لایا.اس کے بعد اگر نوح ؑ دوسرا نبی ہوا ہے تو نوح ؑ کا صحیفہ صحیفتین کہلائے گا کیونکہ اس میں آدم ؑ کا بھی صحیفہ تھا اور نوح ؑ کا بھی صحیفہ تھا.پھر جوں جوں انبیاء ؑآتے گئے وہ اپنے سے پہلے آنے والے انبیاء کی تعلیموں کے بھی حامل رہے یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور آپؐ کو جو کتاب دی گئی اُس میں تمام پہلے انبیاء کے صحیفوں کو شامل کر دیا گیا.اس لئے وہ کتاب کوئی ایک صحیفہ نہیں بلکہ کئی صحف کا مجموعہ ہے اِسی لئے قرآن نے اس کے لئے فِیْ صُحُفٍِ مُّکَرَّمَۃٍ کے الفاظ استعمال فرمائے ہیں.یہ ایسی ہی بات ہے جیسے اِذَاالرُّسُلُ اُقِّتَتْ (المرسلات :۱۲)کہہ کر مسیح موعود علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کی بعثت کی طرف اشارہ کر دیا حالانکہ آنے والا صرف ایک رسول تھا مگر چونکہ اس کی رسالت میں گزشتہ تمام انبیاء کی رسالت بھی شامل ہو جانی تھی اور وہ ہر گزشتہ نبی کا بروز ہونے والا تھا اُسے رسول کی بجائے رُسل کہا گیا.یہی وہ بات ہے جس کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الہام میں بھی ذکر کیا گیا ہے.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جَرِیُّ اللّٰہِ فِیْ حُلَلِ الْاَنْبِیَاءِ (براہین احمدیہ چہار حصص روحانی خزائن جلد ۱ صفحہ ۶۰۱ حاشیہ نمبر ۳)اللہ کا جری جو تمام انبیاء کا لباس پہن کر اس دُنیا میں آیا ہے.اسی طرح قرآن ایک صحیفہ نہیں بلکہ وہ مجموعہ ہے اُن تمام تعلیموں کا جو گزشتہ انبیاء کو دی گئیں اور پھر وہ مجموعہ ہے اُ س زائد تعلیم کا بھی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی.اللہ تعالیٰ فرماتا ہےفِيْ صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ.مَّرْفُوْعَةٍ مُّطَهَّرَةٍۭ یہ قرآن ایسے صحف میں ہے جو مکّرمہ ہیں.مرفوعہ ہیںاور مطّہرہ ہیں.مُّكَرَّمَةٍ.مَّرْفُوْعَةٍ مُّطَهَّرَةٍکے مقابل پر سَفَرَۃٍ،کِرَامٍ ،بَرَرَۃٍ لا کر ایک لطیف مضمون کی
Page 257
طرف اشارہ یہاں ایک لطیف قرآنی ترتیب کا منظر پیش کیا گیا ہے کہ ایک طرف تو قرآن کی یہ تین صفات بیان کی گئی ہیں (۱) مُکَرَّمَۃ (۲) مَرْفُوْعَۃ (۳)مَطَھَّرَۃ اور دوسری طرف وہ لوگ جنہوں نے حاملینِ قرآن بننا تھا اُن کی بھی تین صفات بیان کی گئی ہیں.(۱)سَفَرَۃ(۲)کَرَام(۳)بَرَرَۃ قرآن کریم کی پہلی صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ مُکَرَّمَۃ ہے مُکَرَّمَۃٌ کے معنے عربی زبان میں مُعَظَّمَۃٌ وَمُنَزَّھَۃٌ عَنْ کُلِّ خَطَائٍ وَنَقْصٍ کے ہوتے ہیں یعنی ہر قسم کی خرابی اور نقص سے پاک.گویا پہلی بات قرآن کریم کے متعلق یہ بتائی کہ وہ بزرگ کتا ب ہے اور دُنیا میں اس کی عزت کی جائے گی.یہ ایک قاعدہ کلیہ ہے کہ دُنیا میں جو بھی الہامی کتاب موجود ہے اس کی عزت اِس کتاب کو ماننے والے لوگوں کے دلوں میں پائی جاتی ہے لیکن اِس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ بعض کتابوں کو زیادہ عزت حاصل ہوتی ہے اور بعض کو کم عزت حاصل ہوتی ہے اور جب ہر الہامی کتاب کی اس کے ماننے والے عزت کرتے ہیں تو قرآن کریم کو خاص طور پر مُکَرَّمَۃ کہنا اِس امر کی طرف اشارہ کرتا تھا کہ یہ وہ کتاب ہے جس کی اور تمام الہامی کتابوں سے زیادہ عزت کی جائے گی.کیونکہ وہ کتاب جس کی پہلے ہی عزت کی جاتی ہو جب اُس کے متعلق کہا جائے کہ وہ مُکَرَّمَۃ ہے تو لازمًا اس کے یہ معنے ہوں گے کہ اس کی عزت نسبتی طور پر دوسری کُتب سے بہت زیادہ کی جائے گی.چنانچہ دیکھ لو دُنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں جس کی عزت قرآن کریم سے بڑھ کر کی جاتی ہو.اِس کتاب کو لوگ حفظ کرتے ہیں.یہ کتاب نمازوں میں پڑھی جاتی ہے.اور پھر اس کتاب پر عمل کرنے والی قو م دُنیا میں موجود ہے اور کوئی کتاب ایسی نہیں جس پر عمل کرنے والی قوم دُنیا میں موجود ہو.ویدؔ پر عمل کرنے والے کہیں نظر نہیں آتے.تورات پر عمل کرنے والے بہت شاذونادر دکھائی دیتے ہیں اور جو لوگ عمل کرتے ہیں ان کا عمل اِسی قسم کا ہوتا ہے جسے پنجابی میں ’’اَدھ پچدّھ‘‘ کہتے ہیں یعنی کِسی بات پر عمل کیا اور کسی پر نہ کیا.انجیل تو عملی لحاظ سے بالکل ختم ہے ابھی گزشتہ دنوں انگلستان میں پادریوں نے انجیل کی تعلیم کے خلاف یہ فتویٰ دے دیا تھا کہ عورتیں ننگے سر گرجا میں جا سکتی ہیں.ہمارے مبلغ مولوی جلال الدّین صاحب شمس ؔ نے اُن کو پکڑا کہ تم نے یہ کیا فتویٰ دے دیا تمہاری انجیلی تعلیم تو اس کے مخالف ہے.مگر انہوں نے اس کا کوئی جواب نہ دیا.پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے کہہ دیا شریعت لعنت ہے (گلتیوں باب ۳ آیت ۱۳) جب شریعت اُن کے نزدیک لعنت بن گئی تو اُس پر عمل کرنے کی تحریک اُن کے دلوں میں کس طرح پیدا ہو سکتی ہے.صرف قرآن ہی ایک ایسی کتاب ہے جس پر اس تنزّل کے زمانہ میں بھی عمل کیا جاتا ہے.ہم خواہ غیر احمدیوں کو کچھ کہیں اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ لاکھوں کروڑوں مسلمان آج بھی ایسےنظر آتے ہیں جن کے
Page 258
دلوں میں یہ جذبہ پایا جاتا ہے کہ وہ قرآن پر عمل کریں اور خواہ کس قدر کوئی بے عمل ہو اُس کے دل کے اندرونی گوشوں میں یہ خواہش موجود ہوتی ہے کہ مَیں قرآن پر عمل کروں اور اللہ تعالیٰ کی رضاء حاصل کروں.یہ تو اِ س زمانۂ تنزّل کا حال ہے.اپنے دَور میں تو قرآن پر وہ عمل ہوا ہے کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں.زندگی کے ہر شعبہ پر قرآن نے حکومت کی اور ایسی شاندار حکومت کی جس کی مثال دُنیا کی تاریخ میں اور کہیں نظر نہیں آتی.مُّكَرَّمَةٍکے لفظ میں قرآن مجید کے محفوظ رہنے کی پیشگوئی دوسرے معنے مُکَرَّمَۃ کے مُنَزَّھَۃ عَنْ کُلِّ خَطَائٍ وَنَقْصٍ کے ہوتے ہیں کہ وہ چیز ہر قسم کی خرابی اور نقص سے پاک ہو.یہ خوبی بھی قرآن میں پائی جاتی ہے کہ اِس میں کوئی غیر بات داخل نہیں.اَور تو اَور قرآن کریم میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی قول کو بھی برداشت نہیں کیا جا سکتا.اگر کوئی حدیث ایسی ہو جو صحاح ستّہ میں سے ہر حدیث کی کتاب میں آتی ہو اور ہر محدّث اس حدیث کی صحت پر متفق ہو تو پھر بھی قرآن میں اُس حدیث کو درج نہیں کیا جا سکتا پس خدا نے قرآن کو ایسا بنایا ہے کہ وہ تمام قسم کی غیر باتوں سے پاک ہے یہاں تک کہ ہم دیکھتے ہیں دشمن سے دشمن کو بھی یہ تسلیم کئے بغیر کوئی چارہ نہیں رہتا کہ قرآن ہر قسم کی انسانی دست بُرد سے پاک ہے.میور جیسا شدید دشمن اسلام بھی جو قرآن پر جگہ جگہ اعتراض کرتا ہے جب اس مقام پر پہنچتا ہے تو اُسے سوائے یہ کہنے کے اور کوئی چارہ نہیں رہتا کہ قرآن جس شکل میں آج سے ساڑھے تیرہ سو سال پہلے تھا اسی شکل میں آج بھی موجود ہے.وہ اپنی کتاب میں ایک جگہ اس امر پر بحث کرتا ہے اور کہتا ہے فلاں پادری نے یہ کہا ہے اور فلاں پادری نے یہ لکھا ہے مگر وہ ان سب کےدلائل کو ردّ کرتا ہے اور کہتا ہے سچی بات یہ ہے کہ قرآن کریم سے متعلق ہم یقینی طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس شکل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن دنیا کے سامنے پیش کیا تھا اُسی شکل میں آج بھی موجود ہے.نولڈکے NOLDEKE مشہور جرمن مستشرق بھی قرآن کی اس خوبی کا اعتراف کرتا ہے اور باجود دشمن ہونے کے اُس نے بھی تسلیم کیا ہے کہ قرآن پر یہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ وہ انسانی دستبرد کا شکا ر ہو گیا.نولڈکے NOLDEKEاسلام کا دشمن ہے مگر تمام مستشرقینِ یورپ میں سب سے زیادہ تحقیق اُس نے کی ہے اور میں نے دیکھا ہے بعض دفعہ صحیح حقیقت پر اُس کی غضب کی نظر پڑتی ہے.معلوم ہوتا ہے اُس نے بڑے سچے طور پر قرآن پر غور کیا تھا.وہ بھی اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ میں یہ قطعًا مان نہیں سکتا کہ قرآن میں کوئی اور بات داخل کر دی گئی ہو وہ اسی طرح دوسرے لوگوں کے دخل سے پاک ہے جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں پاک تھا وہ کہتا ہے تم بے شک یہ کہہ لو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن بنایا مگر تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس قرآن میں کوئی تبدیلی ہو گئی.جس طرح وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
Page 259
کے زمانہ میں تھا اُسی طرح وہ اس زمانہ میں بھی ہے(The Encyclopedia Britanica underword Koran ).پس یہ قرآن مُکَرَّمَہ ہے یعنی ہر قسم کی خطاء لفظی ومعنوی سے پاک ہے.اور دنیا کی کوئی کتاب اس خوبی میںقرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتی.سَفَرَةٍکے لفظ میں اس طرف اشارہ کہ قرآن یکدم دنیا میں پھیل جائے گا اس کے مقابلہ میں حاملین قرآن کی جو صفات بیان کی گئی ہیں اُ ن میں سے پہلی صفت سَفَرَۃ ہے گویا مُکَرَّمَۃ کے مقابل پر اللہ تعالیٰ نے سَفَرَۃ کو رکھا ہے اور بتایا ہے کہ اس کی بزرگی کا ذریعہ اللہ تعالیٰ سَفَرَۃ کو بنائے گا.سَفَرَۃ کے معنے یا مسافر کے ہوتے ہیں یا پھر کاتب کے ہوتے ہیں.پہلے معنوں کے لحاظ سے اس میں یہ اشارہ کیا گیا ہے کہ قرآن دنیا میں یکدم پھیل جائے گا کیونکہ وہ اُن لوگوں کے ہاتھ میں ہو گا جو مسافر ہوں گے.مطلب یہ کہ مسلمان اس کو لے کر نکل جائیں گے اور دنیا کے کونہ کونہ میں اس کی تعلیم پہنچا دیں گے.چنانچہ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے معًا بعد کچھ صحابہ ایران میں چلے گئے.کچھ افغانستان میں چلے گئے کچھ چین کی طرف نکل گئے.کچھ جز ائر کی طرف چلے گئے اور اس طرح ایک طرف چین کے انتہائی کناروں تک اور دوسری طرف الجزائر تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہؓ کی زندگی میں ہی قرآن پھیل گیا.گویا جتنی معلومہ دنیا تھی اُس میں قرآن کی تعلیم صحابہ ؓکے ہاتھ سے پھیل گئی بلکہ بعض ممالک کے لوگ اب تک اس بات کے مدعی ہیں کہ صحابہؓ کی لائی ہوئی قرآن کی کاپیاں اُن کے پاس موجود ہیں.توفرماتا ہے بِاَیْدِیْ سَفَرَۃ یہ قرآن اُن لوگوں کے ہاتھ میں ہو گا جو بڑے سفر کرنے والے ہوں گے اور اس طرح قرآن کی اشاعت کا کام سرانجام دیں گے.سَفَرَۃ کے لفظ میں قرآن کے لکھے جانے کی طرف اشارہ سَفَرَۃ کے ایک معنے چونکہ کاتب کے بھی ہیں اس لئے بِاَیْدِیْ سَفَرَۃٍ کہہ کر قرآن کریم کے لکھنے کی طرف اشارہ کیا گیا اور بتایا گیا کہ یہ قرآن اُن لوگوں کے ہاتھ میں جائے گا جو کاتب ہوں گے اور یہ قرآن صرف زبانوں پر ہی نہیں رہے گا بلکہ فوراً ضبط تحریر میں آجائے گا.پس اس آیت سے صحابہؓ کے زمانہ میں ہی قرآن کریم کا لکھا جانا ثابت ہوتا ہے.دشمن اعتراض کرتا ہے کہ قرآن کریم بعد میں لکھا گیا حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے.بِاَیْدِیْ سَفَرَۃٍ جس قوم کے ہاتھ میں ہم یہ قرآن دیں گے وہ اسے فوراً لکھ لے گی صرف زبانوں پر اسے نہیں رہنے دے گی.عیسائی قرآن کریم کے متعلق ہمیشہ یہ اعتراض کیا کرتے ہیں کہ قرآن کو بہت بعد میں لکھا گیا حالانکہ اُن کی اپنی کتاب انجیل کے متعلق تاریخ سے یہ امر ثابت ہے کہ وہ ایک سو اسی سال کے بعد لکھی گئی.اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف جن باتوں کو منسوب کیا جاتا ہے وہ بھی بہت
Page 260
بعد میں لکھی گئیں مگر قرآن کریم وہ کتاب ہے کہ جہاں اسے زبانی یاد کیا جاتا تھا وہاں یہ ایسے لو گوں کے ہاتھ میں بھی تھا جو سَفَرَۃ تھے اسے فوراً لکھ لیتے تھے.چنانچہ تاریخ سے ثابت ہے کہ صحابہ کرامؓ کی موجودگی میں ہی سارا قرآن لکھا گیا تھا.اس میں اس طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ قرآن کی تمام دنیا میں عزت کی جائے گی کیونکہ وہ بِاَیْدِیْ سَفَرَۃٍ ہو گا.جو تعلیم کسی ایک ملک میں محدود ہو گی لازماً اُس کا اکرام اَور رنگ کا ہو گا.اور جو سارے ملکوں میں ہوگی اس کا اکرام اور رنگ کا ہوگا.پس چونکہ قرآن سفر کرنے والے لوگوں کے ہاتھ میں ہو گا اس قرآن کی تکریم بھی ساری دنیا میں ہو گی.کسی ایک ملک میں نہیں ہو گی.پھر سَفَرَۃ کے معنے خالی لکھنے کے نہیں ہوتے بلکہ اس کے مادہ میں انکشاف کے معنے بھی پائے جاتے ہیں پس بِاَیْدِیْ سَفَرَۃٍ کہہ کر اس امر کی طرف بھی اشارہ کیا گیا کہ اُسے ایسے لکھنے والے لکھیں گے جو اس کے مطالب کو واضح کریں گے اور اس کے اخلاق کو کھولیں گے گویا بِاَیْدِیْ سَفَرَۃٍ کے معنے یہ ہوئے کہ قرآن اُن لوگوں کے ہاتھ میں ہو گا جو اس کی تفسیریں کرنے والے ہوں گے.اس کے حقائق کو واضح کرنے والے ہوں گے اور اس کی پوشیدہ اور متعلق باتوں پر سے پردہ اٹھانے والے ہوں گے اور اس طرح قرآن نہ صرف خطاء لفظی سے پاک ہو گا بلکہ وہ خطاء معنوی سے بھی پاک ہو گا.سَفَرَۃ چونکہ مُکَرَّمَۃ کے مقابل میںہے اس لئے اس آیت کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کریم کو ماننے والے اس کی بڑی عزّت کریں گے اور نہ صرف خود عزّت کریں گے بلکہ ساری دنیا میں پھیل کر ساری دنیا سے اس کی عزّت کرائیں گے.تیسری طرف اس قرآن کو محفوظ رکھیں گے اور اس طرح قرآن کی عزّت میں اور بھی اضافہ ہو گا.جیسے میں نےمیور (MUIR)اور نولڈکے (NOLDEKE) کے متعلق بتایا ہے کہ باوجود شدید دشمن اسلام ہونے کے وہ اس بات کو تسلیم کرنے پر مجبور ہوئے ہیں کہ قرآن پوری طرح محفوظ ہے.پس قرآن کے ضبط تحریر میں آجانے کی وجہ سے اس کے اعزاز میں اَور بھی اضافہ ہو گیا یہاں تک کہ دشمن بھی اس اعزاز کو تسلیم کئے بغیر نہیں رہ سکے.پھر قرآنی معارف کی تشریح کے لحاظ سے بھی اس کی تکریم میں غیر معمولی اضافہ ہوا کیونکہ قرآن کی نہ صرف ظاہری حیثیت قائم رہی بلکہ اس کی معنوی حیثیت بھی قائم رہی.اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں قرآن دیا جو اس کے اغلاق کو کھولنے والے اور اس کے مطالب کی وضاحت کرنے والے تھے.اس میں اس امر کی طرف بھی اشارہ تھا کہ قرآن کی بولی دنیا میں بولی جائے گی یہ زبان زندہ رہے گی اور اس کے مضامین کو حل کرنے کے لئے لوگوں کو کسی قسم کی دقّت پیش نہیں آئے گی.
Page 261
مرفوعۃ کے لفظ کا ظاہری معنے کے لحاظ سے پورا ہونا دوسری صفت اللہ تعالیٰ نے مَرْفُوْعَۃٌ بیان فرمائی ہے.رَفَعَ کے معنے ہوتے ہیں اونچا کیا.یعنی ذلّت نہ کی بلکہ اعزاز کیا.اس کے مقابلہ میں صحابہؓ کے متعلق فرماتا ہے کہ وہ کِرَامٌ ہوں گے اور کِرَامٌ کے معنے بزرگ کے ہوتے ہیں اس جگہ قرآن کے متعلق مَرْفُوْعَۃٌ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اور جیسا کہ میں بتا چکا ہوں مَرْفُوْعَۃٌ کے معنے ذی شان ہونے کے ہیں.یہ بات ظاہری لحاظ سے بھی قرآن کریم کے متعلق پائی جاتی ہے.چنانچہ دیکھ لو قرآن کو اُمت محمدؐیہ کبھی نیچا نہیں رکھتی ہمیشہ اُسے اُونچی جگہ پر رکھا جاتا ہے بلکہ اگر کوئی شخص قرآن کریم کو نیچے رکھ دے تو سب مسلمان اس سے لڑنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں کہ تم نے قرآن کریم کی ہتک کی.پس ظاہر میں بھی یہ معنے قرآن کریم پر چسپاں ہو جاتے ہیں کیونکہ مسلمان جس طرح قرآن کو اُنچا رکھتے ہیں دُنیا کی کوئی عالمگیر قوم اپنی الہامی کتاب کی اس طرح عزت نہیں کرتی.درحقیقت اور کوئی عالمگیر قوم اپنی کتاب کو اونچا رکھنے کی عادی ہی نہیں.نہ عیسائی انجیل کو اونچا رکھتے ہیں نہ یہودی تورات کو اونچا رکھتے ہیں.یہ شرف صرف قرآن کریم کو ہی حاصل ہے کہ مسلمان اس کو اونچی جگہ پر رکھتے ہیں.اس کو نیچے رکھنا وہ برداشت ہی نہیں کر سکتے.مَیں نے بتایا تھا کہ قرآن کریم کی تین صفات جو اِس جگہ بیان کی گئی ہیں وہ حاملینِ قرآن کی تین صفات کے مقابل میں رکھی گئی ہیں اوراس طرح بتایا گیا ہے کہ ان میں سے ایک چیز دوسری چیز کا سبب ہے چنانچہ دیکھ لو قرآن مُکْرَّمَۃ ہو گیا اس لئے کہ وہ سَفَرَۃ کے ہاتھ میں تھا جو اُسے لے کردُنیا کے مختلف مُلکوں میں پھیل گئے اور سَفَرَۃ.مُکَرَّم ہو گئے اس لئے کہ اُن کے ہاتھوں میں وہ کتاب تھی جو بڑی عزت والی تھی.گویا یہ دونوں باتیں ایک دوسرے سے لازم ملزوم تھیں.یہ جوش جو کسی شخص کے دل میں پیدا ہوتا ہے کہ مَیں اس چیز کو اپنے ہاتھ میں لیکر باہر نکل جائوں اسی لئے پیدا ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کو مُکَرَّمَۃ سمجھتا ہے اور اُسے یقین ہوتا ہے کہ اس چیز کو پھیلانا میری عزت کا موجب ہے مگر جب وُہ اسے پھیلا دیتا ہے تو اس کا طبعی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ خود بھی مکرّم بن جاتا ہے کیونکہ وہ ایسی چیز کو پھیلاتا ہے جو تکریم رکھنے والی ہوتی ہے.گویا قرآن کا مُکَرَّم ہونا سَفَرَۃ کی وجہ سے تھا اور سَفَرَۃ کا مُکَرَّم ہونا قرآن کی وجہ سے تھا.قرآن مسلمانوں کی عزت کا باعث ہوا.اور مسلمان قرآن کی عزت کو بڑھانے کا باعث ہوئے جیسے ایک مشینری چکّر کھاتی چلی جاتی ہے اُسی طرح ایک طرف قرآن نے صحابہؓ کو اونچا کیا اور دوسری طرف صحابہؓ نے قرآن کو اونچا کیا.صحابہؓ قرآن کی عزت بڑھانے کا موجب ہوتے تھے اور قرآن صحابہؓ کی عزت بڑھانے کا موجب ہوتا تھا.
Page 262
دوسری صفت قرآن کی مَرْفُوْعَۃ بتائی کہ وہ بڑی ذی شان کتاب ہے.ا ب یہ لازمی بات ہے کہ جس شخص کے پاس کوئی ذی شان چیز ہو گی وہ ضرور کِرَامٌ بن جائے گا.مگر دوسری طرف جس چیز کی کِرَامٌ عزت کریں وہ بھی ذی شان اور معزز ہو جاتی ہے چنانچہ دیکھ لو جب کوئی معزز آدمی کسی کی عزت کرے گا لوگ کہیں گے کہ معلوم ہوتا ہے یہ شخص بڑی عزت والا ہے کیونکہ فلاں معزز آدمی نے اس کی عزت کی تھی.پس وہ اس کی عزت کرنے پر مجبور ہوں گے.اور جب وہ معزز بن کر پھر دوسرے کی عزت کرے گا تو اس کی شہرت میں بھی اضافہ ہو گا کہ اسے فلاں معزز آدمی عزت کی نگا ہ سے دیکھتا ہے.گویا یہ ایک سِلسلہ ہے جو مشینری کی طرح چکّر کھاتا چلا جاتا ہے.جو لوگ خود کسی چیز کے اوصاف سے ذاتی طور پر واقف نہ ہوں وہ اگر اُس چیز سے متاثر ہوتے ہیں تو اُسی وقت جب وہ دیکھیں کہ کوئی بڑاآدمی جس کا اُس کے دل میں احترام موجود ہے اُس چیز کی تعریف کر ر ہا ہے یہ دیکھ کر وہ خود بھی اُس کے مدّاح بن جاتے ہیں.اب جو قرآن کریم پر ایمان رکھتے تھے وہ تو اُس کی عزت کرتے ہی تھے مگر ایک عیسائی کے نزدیک قرآن کریم کی عظمت کا سب سے بڑا ثبوت یہ تھا کہ روم کے بادشاہ کو بھی اس کی عظمت کا احساس ہے اور وہ کہتا ہے یہ بہت بڑی کتاب ہے جسے عمرؓ جیسا عظیم الشان انسان مانتا ہے حالانکہ عمرؓ کیوں بڑے بنے اسی لئے کہ انہوں نے قرآن پر عمل کیا.گویا ایک طرف روما کا بادشاہ یہ کہے گا کہ قرآن بڑی کتاب ہے جس کو عمرؓ جیسا انسان مانتا ہے اور دوسری طرف عمرؓ کی حقیقت کو جاننے والا یہ کہے گا کہ قرآن بڑی کتاب ہے کیونکہ اس کو ماننے والا عمرؓ ادنیٰ حالت سے ترقی کر کے اِس قدر بڑا بن گیا.غرض جب سچّی باتیں ایک دوسرے کے مقابل میں آجاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ وہ ایک دوسرے کو اُبھارتی چلی جاتی ہیں.اِسی لئے فرمایا کہ قرآن مَرْفُوْعَۃ ہے یعنی بڑی ذی شان کتاب ہے اور اس کے ذی شان ہونے کا ثبوت یہ ہو گا کہ اس کے ساتھ تعلق رکھنے والے عزت پاتے چلے جائیں گے اور جب وہ عزت پا جائیں گے تو پھر قرآن کو ایک نئی عزت حاصل ہو گی کیونکہ لوگ کہیں گے کہ اِس کتاب کو تو بڑے بڑے معززآدمی مانتے ہیں پھر یہ بات دوبارہ چکّر کھائے گی کہ قرآن کریم کی نئی حاصل کر دہ عزت کی وجہ سے کچھ اور لوگ اس کا عملی تجربہ کرنے کی طرف متوجہ ہوں گے اور اس کی اتباع سے عزّت پائیں گے اور پھر اور لوگ ان کی عزّت کو دیکھ کر قرآن کریم کی عزّت کے قائل ہوںگے اور اِسی طرح یہ سلسلہ چلتا چلا جائے گا.قرآن لوگوں کو کرام بنائے گا اور لوگ قرآن کو مرفوعہ بنائیں گے گویا پہلے مُکَرَّمَۃ کے ذریعہ سے قرآن کریم کی ذاتی عزت بتائی پھر مَرفُوْعَۃ کے ذریعہ سے بتایا کہ قرآن مسلمانوں کو کِرَامٌ بنا دے گا اور وہ اسے مَرْفُوْعَۃ بنا دیں گے.مسلمان سارے عالم پر چھا جائیں گے اور اس طرح پھر دوسری قسم کی عزّت قرآن کریم کو ملے گی یعنی بادشاہوں کا محبوب
Page 263
دوسری صفت قرآن کی مَرْفُوْعَۃ بتائی کہ وہ بڑی ذی شان کتاب ہے.ا ب یہ لازمی بات ہے کہ جس شخص کے پاس کوئی ذی شان چیز ہو گی وہ ضرور کِرَامٌ بن جائے گا.مگر دوسری طرف جس چیز کی کِرَامٌ عزت کریں وہ بھی ذی شان اور معزز ہو جاتی ہے چنانچہ دیکھ لو جب کوئی معزز آدمی کسی کی عزت کرے گا لوگ کہیں گے کہ معلوم ہوتا ہے یہ شخص بڑی عزت والا ہے کیونکہ فلاں معزز آدمی نے اس کی عزت کی تھی.پس وہ اس کی عزت کرنے پر مجبور ہوں گے.اور جب وہ معزز بن کر پھر دوسرے کی عزت کرے گا تو اس کی شہرت میں بھی اضافہ ہو گا کہ اسے فلاں معزز آدمی عزت کی نگا ہ سے دیکھتا ہے.گویا یہ ایک سِلسلہ ہے جو مشینری کی طرح چکّر کھاتا چلا جاتا ہے.جو لوگ خود کسی چیز کے اوصاف سے ذاتی طور پر واقف نہ ہوں وہ اگر اُس چیز سے متاثر ہوتے ہیں تو اُسی وقت جب وہ دیکھیں کہ کوئی بڑاآدمی جس کا اُس کے دل میں احترام موجود ہے اُس چیز کی تعریف کر ر ہا ہے یہ دیکھ کر وہ خود بھی اُس کے مدّاح بن جاتے ہیں.اب جو قرآن کریم پر ایمان رکھتے تھے وہ تو اُس کی عزت کرتے ہی تھے مگر ایک عیسائی کے نزدیک قرآن کریم کی عظمت کا سب سے بڑا ثبوت یہ تھا کہ روم کے بادشاہ کو بھی اس کی عظمت کا احساس ہے اور وہ کہتا ہے یہ بہت بڑی کتاب ہے جسے عمرؓ جیسا عظیم الشان انسان مانتا ہے حالانکہ عمرؓ کیوں بڑے بنے اسی لئے کہ انہوں نے قرآن پر عمل کیا.گویا ایک طرف روما کا بادشاہ یہ کہے گا کہ قرآن بڑی کتاب ہے جس کو عمرؓ جیسا انسان مانتا ہے اور دوسری طرف عمرؓ کی حقیقت کو جاننے والا یہ کہے گا کہ قرآن بڑی کتاب ہے کیونکہ اس کو ماننے والا عمرؓ ادنیٰ حالت سے ترقی کر کے اِس قدر بڑا بن گیا.غرض جب سچّی باتیں ایک دوسرے کے مقابل میں آجاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ وہ ایک دوسرے کو اُبھارتی چلی جاتی ہیں.اِسی لئے فرمایا کہ قرآن مَرْفُوْعَۃ ہے یعنی بڑی ذی شان کتاب ہے اور اس کے ذی شان ہونے کا ثبوت یہ ہو گا کہ اس کے ساتھ تعلق رکھنے والے عزت پاتے چلے جائیں گے اور جب وہ عزت پا جائیں گے تو پھر قرآن کو ایک نئی عزت حاصل ہو گی کیونکہ لوگ کہیں گے کہ اِس کتاب کو تو بڑے بڑے معززآدمی مانتے ہیں پھر یہ بات دوبارہ چکّر کھائے گی کہ قرآن کریم کی نئی حاصل کر دہ عزت کی وجہ سے کچھ اور لوگ اس کا عملی تجربہ کرنے کی طرف متوجہ ہوں گے اور اس کی اتباع سے عزّت پائیں گے اور پھر اور لوگ ان کی عزّت کو دیکھ کر قرآن کریم کی عزّت کے قائل ہوںگے اور اِسی طرح یہ سلسلہ چلتا چلا جائے گا.قرآن لوگوں کو کرام بنائے گا اور لوگ قرآن کو مرفوعہ بنائیں گے گویا پہلے مُکَرَّمَۃ کے ذریعہ سے قرآن کریم کی ذاتی عزت بتائی پھر مَرفُوْعَۃ کے ذریعہ سے بتایا کہ قرآن مسلمانوں کو کِرَامٌ بنا دے گا اور وہ اسے مَرْفُوْعَۃ بنا دیں گے.مسلمان سارے عالم پر چھا جائیں گے اور اس طرح پھر دوسری قسم کی عزّت قرآن کریم کو ملے گی یعنی بادشاہوں کا محبوب ہونے کے سبب سے سب دُنیا میں مَرْفُوْعَۃ ہو جائے گا کہ سب اسے اپنے سروں پر رکھیں گے.تیسری صفت قرآن کریم کی مُطَھَّرَۃ بیان کی گئی ہے اور مُطَھَّرَۃ کے معنے پاکیزہ کے ہوتے ہیں اس کے مقابل میں بَرَرَۃ کو رکھا گیا ہے جو بَرَّ سے ہے اور بَرَّ کے معنے ہوتے ہیں اَحْسَنَ الطَّاعَۃَ اِلَیْہِ وَرَفَقَ وَتَحَرَّی مَحَابَّہٗ وَتَوَقّٰی مَکَارِہَہٗ (اقرب)کہ اس کی پوری طرح اطاعت کر.اُس کے ساتھ رفق کیا.اور اُس کی اچھی چیزوں کو خوب شوق سے حاصل کیا یا اُس کی طرف توجہ سے کام لیا اور اس کی ناپسندیدہ باتوں سے بچا.یہ کتنا چھوٹا سالفظ ہے مگر اس کے اندر کتنے وسیع معنے ہیں اور کس طرح اس ایک لفظ میں ہی حاملین قرآن کے اوصاف کو بیان کر دیا گیا ہے.اس لحاظ سے بَرَرَۃ کے معنے یہ ہوئے کہ وہ قرآن کی پوری اطاعت کرنے والے ہوں گے.اُس کے ساتھ اپنا پوراتعلق رکھیں گے.جو چیزیں اُس نے پسند کی ہیں اُن کو وہ پُورے زور سے حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اور جن چیزوں سے اُس نے منع کیا ہے اُن سے وہ پُورے زور سے بچیں گے.قرآن کریم کے متعلق مُطَہَّرَۃ اور صحابہ کے متعلق بَرَرَۃ کا لفظ استعمال کر کے اللہ تعالیٰ نے اِس طرف اشارہ کیا ہے کہ قرآن کریم اپنے اندر کوئی ایسی بات نہیں رکھتا جو فطرتِ انسانی کے خلاف ہو.تمام باتیں جو فطرتِ انسانی کو اُبھارنے والی ہیں وہ اُس کے اندر موجود ہیں اور تمام باتیں جو فطرتِ انسانی کو بگاڑنے والی ہیں اُن سے وہ پاک ہے.اِس وجہ سے وہ لوگ جو اس کتاب سے تعلق رکھنے والے ہوں گے وہ بھی ایسے ہی ہوں گے کہ اس کی ساری باتوں پر عمل کریں گے اور اُن ساری باتوں سے بچنے کی کوشش کریں گے جن سے قرآن کریم نے روکا ہے.غرض بَرَرَۃ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ مومن اپنا پُورا زور اِس بات پر صرف کریں گے کہ قرآن کریم نے جن باتوں پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے اُن پر عمل کریں اور وہ پُورا زور اس بات پر صرف کریں گے کہ قرآن کریم نے جن باتوں سے منع کیا ہے اُن سے مجتنب رہیں اور اِس طرح وہ بَرَرَۃ ہوں گے یعنی اس کے نتیجہ میں کامل متقی بن جائیں گے.جب انسان اِس مقام پر نہیںہوتااور وہ اِسی شش و پنج میں مبتلا رہتا ہے کہ مَیں قرآن کریم کی بات کو مانوں یا نہ مانوں تو وہ بَرَرَۃ میں شامل نہیں سمجھا جا سکتا.اور نہ وہ قرآن کو مُطَھَّرسمجھنے والا قرار دیا جا سکتا ہے کیونکہ اگر وہ قرآن کریم کو مُطَھَّر سمجھتا اور یقین رکھتا کہ قرآن کریم نے ہر وہ تعلیم دی ہے جس کی فطرتِ انسانی کو پیاس ہے اور ہر اُس بات سے روکا ہے جو فطرت کو مسخ کرنے والی ہے تو وہ اس کے احکام پر عمل بھی کرتا اور اُس کے نواہی سے بچنے کی بھی کوشش کرتا مگر جب وہ ایسا نہیں کرتا تو اس کے معنے یہی ہوتے ہیں کہ نہ وہ قرآن کے مطہر ہونے پر ایمان رکھتا ہے اور نہ اپنے آپ کو بَرَرَۃ میں شامل کرنا چاہتا ہے اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مُطَھَّرَۃ کے مقابل میں بَرَرَۃ رکھا یہ بتانے کے
Page 264
لئے کہ ان دونوں میں نسبت پائی جاتی ہے.جب قرآن پر عمل کرنے کے نتیجہ میں لوگ بَرَرَۃ بن جائیں گے تو وہ قرآن کو نئے سرے سے مطہر بنائیں گے اس لئے کہ جب انسان نیکو کار ہو گا.قرآن پر عمل کرے گا.اللہ تعالیٰ کے احکام کو مدنظر رکھے گا تو یہ لازمی بات ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے اُس پر روحانی فیوض کا نزول ہو گا کیوں کہ جب انسان نیکیوں میں حصّہ لیتا اور اللہ تعالیٰ کے قرب میںبڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو اُس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیوض نازل ہوتے ہیں.جب بَرَرَۃ پر قرآن کریم پر عمل کرنے کے نتیجہ میں فیوض نازل ہوں گے تو وہ ان فیوض کو قرآن کریم کی طرف منسوب کریں گے اور اس طرح قرآن کریم کو ایک نئے رنگ کی طہارت حاصل ہو جائے گی جیسے قرآن کریم تو پہلے ہی مطہر تھا مگر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے مبعوث ہو کر اسے جس طرح مطہر کیا اس سے پہلے اور کسی نے نہیں کیا مگر سوال یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کو کس نے بَرَرَۃ میں سے بنایا تھا؟اسی قرآن نے گویا قرآن نے مسیح موعودؑ کو پاک کیا اور مسیح موعودؑ نے قرآن کی طہارت کے پوشیدہ اوصاف کو ظاہر کیا.حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بعثت سے پہلے لوگ قرآن کریم کی طرف کئی قسم کی غلط باتیں منسوب کیا کرتے تھے مگر آپ نے اُن تمام غلط عقائد اور غلط تعلیمات کا باطل ہونا ثابت کر دیااور اس طرح قرآن کو مطہر بنا دیا.جب آپ نے قرآن کو مطہر بنایا تو یہ لازمی بات تھی کہ اس کے نتیجہ میں آپ کی نیکیوں میں اَور بھی اضافہ ہو جاتا پس قرآن کی تیسری صفت یہ ہے کہ وہ مطہر ہے اُس پر عمل کرنے والے بَرَرَۃ میں شامل ہو جاتے ہیں اور بَرَرَۃ میں شامل ہونے والے پھر قرآن کو مطہر کرتے ہیں اور قرآن اُن کو پھر نیکیوں میں بڑھاتا ہے اور اس طرح یہ سلسلہ چلتا چلا جاتا ہے.مذکورہ بالا امور سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اس کلام کی عظمت کسی ظاہری سامان کی محتاج نہیں بلکہ قلوب کی صفائی کے ساتھ قرآن کریم کی عظمت قائم ہوتی ہے.گویا بتایا گیا ہے کہ اس قرآن سے وہی لوگ فائدہ اٹھائیں گے جو نیک ہوں مگر وہ لوگ فائدہ نہیں اٹھا سکتے جو نیک نہیں ہیں.اور جب یہ بات ہے تو پھر یہ کوئی سوال ہی نہ رہا کہ ظاہر میں فلاں شخص بڑا ہے اور فلاں شخص چھوٹا.فلاں شخص عالم ہے اور فلاں شخص جاہل.کیونکہ یہاں ظاہری بڑائی یا ظاہری علم یا ظاہری عزّت کا کوئی سوال نہیں.قرآن ایسے ہی ہاتھوں میں ترقی کرے گا جو سَفَرَۃ ہوں گے.کِرَامٌ ہوں اور بَرَرَۃ کے اوصاف اپنے اندر رکھتے ہوں گے خواہ وہ ظاہری طور پر بڑوں میں سے ہوں یا چھوٹوں میں سے.امیروں میں سے ہوں یا غریبوں میں سے.چنانچہ مکّہ کے چوٹی کے خاندانوں میں سے بھی اللہ تعالیٰ نے کئی لوگوں کو خدمت کی توفیق دی اور غرباء میں سے بھی کئی لوگوں نے اسلام کی شاندار خدمات سرانجام دیں.چنانچہ دیکھ لو
Page 265
حضرت علیؓ چوٹی کے خاندان میں سے تھے.حضرت حمزہؓ چوٹی کے خاندان میں سے تھے.حضرت عمرؓ چوٹی کے خاندان میں سے تھے.حضرت عثمانؓ چوٹی کے خاندان میں سے تھے اس کے بالمقابل زیدؓ اور بلالؓ اور سمرہؓ اور خُبابؓ.صُہیبؓ.عامرؓ.عمارؓ.ابوفکیہہؓ چھوٹے سمجھے جانےوالوں میں سے تھے.گویا بڑے لوگوں میں سے بھی قرآن کریم کے خادم چُنے گئے اور چھوٹے لوگوں میں سے بھی.پس فرماتا ہے تمہارا یہ سوال بالکل غلط ہے کہ یہ لوگ آئیں گے کہاں سے؟ اسی طرح تمہارا یہ خیال بھی غلط ہے کہ فلاں شخص ہی دین کے قابل ہے اور فلاں نہیں.یہ معاملہ قلوب سے تعلق رکھتا ہے ظاہر سے نہیں.اور اس وجہ سے ہم ان لوگوں کا خود انتخاب کریں گے.قرآن کریم میں وہ تمام چیزیں موجود ہیں جو اچھے لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں اور اگر کسی شخص کو قرآن کریم کی خوبیاں نہیں کھینچ سکیں تو وہ یقینا اس زمانہ میں حقیقی بڑائی حاصل کرنے کا مستحق ہی نہیں.قُتِلَ الْاِنْسَانُ مَاۤ اَكْفَرَهٗؕ۰۰۱۸ انسان ہلاک ہو وہ کیسا ناشکرا ہے.حَلّ لُغَات.قُتِلَ قُتِلَ قَتَلَ سے مجہول کا صیغہ ہے اور قَتَلَ اللّٰہُ الْاِنْسَانَ کے معنے ہیں لَعَنَہُ اللہ نے اُس پر لعنت کی (اقرب) پس قُتِلَ الْاِنْسَانُ کے معنی ہوں گے.اس انسان پر لعنت ہو.تفسیر.قُتِلَ الْاِنْسَانُ میں قرآن سے اعراض کرنے والے سے خطاب جس قسم کا لطیف نقشہ قرآن کریم کی خوبیوں اور اُس کے کمالات کا اوپر کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے کھینچا ہے اس کی مناسبت سے فرماتا ہے قُتِلَ الْاِنْسَانُ مَآ اَکْفَرَہٗ.یہ منکر انسان جو قرآن کریم سے اعراض کرنے والا اور اُس کے احکام سے تَلھِّی اختیار کرنے والا ہے کتنا بڑا ناشکر گزار انسان ہے اس کے سامنے ایک ایسا عظیم الشان کلام پیش کیا جا رہا ہے جو مکّرمہ ہے جو مرفوعہ اور مطہرہ ہے اور جو نہ صرف آپ ہی پاک ہے بلکہ اس کے اندر یہ خصوصیت بھی موجود ہے کہ جو شخص اس کو ہاتھ لگا لے وہ بھی پاک ہو جاتا ہے گویا جیسے سنگ پارس کے متعلق یہ مشہور ہے کہ وہ جس چیز سے چُھو جائے سونا بن جاتی ہے اسی طرح یہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ نہ صرف خود اعزاز رکھنے والی ہے بلکہ جو لوگ اس پر عمل کرتے ہیں وہ بھی معزز بن جاتے ہیں نا صرف خود پاک ہے بلکہ جو اس پر عمل کرتے ہیں وہ بھی پا ک بن جا تے ہیں.جب یہ ایسی عظیم الشان کتاب ہے تو قُتِلَ الْاِنْسَانُ مَآ اَکْفَرَہٗ.اس قرآن سے اعراض کرنے والا انسان ہلاک ہو وہ کتنا بڑا
Page 266
ناشکرا ہے قرآن اس کے سامنے تھا اور اس کے لئے موقع تھا کہ وہ اس کے احکام پر عمل کر کے سَفَرَۃ میں سے بن جاتا.کِرَامٌ میں سے بن جاتا.بَرَرَۃ میں سے بن جاتا.اگر قرآن کے اندر صرف ذاتی خوبیاں ہوتیں تو کوئی شخص کہہ سکتا تھا کہ مجھے تو وہ خوبیاں اس کلام میں نظر نہیں آئیں مگر قرآن کی خوبیان وہ ہیں جو صرف ذاتی نہیں بلکہ متعدی ہیں اور دوسروں کے اندر بھی پیدا ہو جاتی ہیں.پس یہ انسان کیسا ناشکرا ہے کہ ہم نے تو اسے بڑھانے اور ترقی دینے کا سامان کیا مگر وہ اُلٹا اس کلام سے دُور بھاگتا ہے.مِنْ اَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهٗؕ۰۰۱۹مِنْ نُّطْفَةٍ١ؕ خَلَقَهٗ فَقَدَّرَهٗۙ۰۰۲۰ (وہ غور تو کرے) کہ کس چیز سے خدا نے اُسے پیدا کیا ہے نطفہ سے (پیدا کیا ہے) (پہلے تو)اُسے پیدا کیا پھر اس ثُمَّ السَّبِيْلَ يَسَّرَهٗۙ۰۰۲۱ کے لئے (ترقی کا ایک) اندازہ مقرر کیا.پھر (اس کے) راستہ کو (آسان بنایا) خوب ہی (اُسے) آسان بنایا.تفسیر.آخر وہ یہ تو سوچے کہ ہم نے اُس کی پیدائش کس طرح کی ہے اور کن اعلیٰ اور بلند اغراض کے لئے اُسے دُنیا میں بھیجا ہے.قرآن کریم کا یہ ایک عجیب وصف ہے کہ ایک طرف تو وہ اپنی شان کا اظہار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں تمہاری کوئی پرواہ نہیں.اگر تم مانو گے تو تمہارا اپنا فائدہ ہو گا اور اگر انکار کرو گے تو تمہارا اپنا نقصان ہو گا.مگر دوسری طرف جس طرح ماں کے دل میں اپنے بچہ کے متعلق رحم اور محبت کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں اسی طرح قرآن کریم میں پیدا ہو جاتے ہیں اور پھر محبت اور پیار سے اُن کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرتا ہے.ماں بھی اسی طرح کرتی ہے جب بچہ اس کا کہنا نہیں مانتا تو وہ ناراض ہو کر کہتی ہے کہ میرا کیا ہے میں نے تو تمہارے فائدہ کے لئے یہ بات کہی تھی مگر تھوڑی دیر کے بعد ہی وُہ پھر اُسے پُچکار کر کہنا شروع کر دیتی ہے کہ بچے کھانا کھا لے.اور اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح بچہ اس کی بات مان لے.مِنْ اَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهٗکہہ کر لطیف طریقہ سے قرآن پر غور کرنے کی تلقین اسی طرح قُتِلَ الْاِنْسَانُ مَآاَکْفَرَہٗ میں اللہ تعالیٰ نے استغناء ظاہر کیا تھا کہ انسان ہلاک ہو جائے وہ کتنا بڑا ناشکر ا ہے قرآن جیسی کتاب اس کے سامنے پیش کی جاتی ہے اور وہ پھر بھی تَلَھِّی اور اعراض سے کام لیتا ہے مگر یہ کہنے کے معًا بعد فرما دیا مِنْ اَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهٗ.مِنْ نُّطْفَۃٍ.گویا انسان کو پچکارنا شروع کر دیا کہ کسی طرح وہ اُس کی طرف واپس آجائے.فرماتا ہے کیا
Page 267
انسان اس بات پر بھی غور نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ اُسے کس طرح پیدا کرتا ہے مِنْ نُّطْفَۃٍ وہ اسے ایک چھوٹے سے قطرہ سے پیدا کرتا ہے اور پھر پیدا کرنے کے بعد اُس نے اُسے چھوڑ نہیں دیا بلکہ فَقَدَّرَہٗ اس کا اندازہ مقرر کیا قَدَّرَہٗ کے متعلق مفردات والا لکھتا ہے کہ اَشَارَۃٌ اِلٰی مَا اَوْ جَدَہٗ فِیْہِ بِالْقُوَّۃِ فَیَظْھَرُ حَالًا فَحَالًا اِلَی الْوُجُوْدِ بِالصُّوْرَۃِ کہ وہ مخفی قوتیں جو خدا تعالیٰ نے انسان میںرکھی ہیں اور جن کو موقع موقع پر انسان ظاہر کرتا چلا جاتا ہے اُن کی طرف اس آیت میں اشارہ کیا گیا ہے گویا خَلَقَہٗ فَقَدَّرَہٗ کے معنے یہ ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور پھر اس میں ایسی طاقتیں اور قوتیں رکھیں جو ہر موقع و محل کے مطابق اس سے ظاہر ہوتی رہتی ہیں.جیسا کام ہوتا ہے ویسی ہی قوتیں اس سے ظاہر ہونی شروع ہو جاتی ہیں.گویا ایک وسیع ترقی کا میدان اللہ تعالیٰ نے اُس کے لئے پیدا کیا ہے.ثُمَّ السَّبِيْلَ يَسَّرَهٗ کا مطلب ثُمَّ السَّبِيْلَ يَسَّرَهٗ اِدھر اُس نے انسان کے لئے ترقی کا ایک وسیع میدان پیدا کیا ہے اور اُدھر اس کے اندر ایسا مادہ رکھ دیا ہے کہ جب بھی کوئی اہم موقع اُس کے سامنے آئے اس کے مطابق اس کی اندرونی قابلیتیں اُبھر کر سامنے آجاتی ہیں اور اُسے کوئی قربانی بھی دوبھر محسوس نہیں ہوتی.پس ثُمَّ السَّبِیْلَ یَسَّرَہٗ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایسا مادہ پیدا کر دیا ہے کہ اگر وہ اپنی طبیعت پر ذرا بھی بوجھ ڈال لے تو ہر کام اس کے لئے آسان ہو جاتا ہے اور وہ بڑی بڑی دشوار گزارگھاٹیاں آسانی سے عبور کر جاتا ہے.لوگ کہتے ہیں کہ عادت بُری چیز ہے لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عادت بھی ہمارے فضلوں میں سے ایک فضل ہے.اور جب کسی کام کی عادت انسان کو ہو جائے تو پھر اس کام کے کرتے وقت کوئی دِقّت محسوس نہیں ہوتی.پس کسی کام کی عادت ہو جانا ایک خوبی ہے بشرطیکہ اس عادت کا استعمال کسی بُرے موقع پر نہ ہو.پس فرماتا ہے ثُمَّ السَّبِيْلَ يَسَّرَهٗ.انسان کو پیدا کرنے اور اس کے اندر ترقی کی قابلیتیں رکھنے کے بعد ہم نے اُس کا راستہ آسان کر دیاہے.نماز پڑھنا پہلے انسان کو بڑا دوبھر معلوم ہوتا ہے مگر کچھ دن باقاعدگی اور التزام سے نمازیں پڑھنے کے بعد ایسی عادت ہو جاتی ہے کہ نمازوں کا پڑھنا بالکل آسان معلوم ہونے لگتا ہے.روزے رکھنے لگیں تو پہلے مشکل معلوم ہوتے ہیں لیکن جب روزوں کی عادت ہو جائے تو پھر محسوس بھی نہیں ہوتا کہ یہ بھی کوئی مشکل کام ہے.یہی حال صدقہ و خیرات اور دوسری نیکیوں کا ہے.جن لوگوں کو صدقہ و خیرات کی عادت ہو جائے ہم نے دیکھا ہے کہ جب تک وہ روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ نہ کرلیں انہیں چین ہی نہیں آتا.عربوں کو اس بات کی عادت تھی کہ وہ کھانا کھاتے وقت کسی اَور کو اپنے ساتھ ضرور شریک کر لیا کرتے تھے اور پھر یہ عادت رفتہ رفتہ ایسی پختہ ہو گئی کہ جب تک وہ کسی اَور کو اپنے ساتھ دسترخوان پر نہیں بٹھا لیتے تھے وہ کھانا نہیں کھا سکتے تھے اور تلاش کر کر کے دوسروں کو اپنے کھانے میںشریک
Page 268
کرتے تھے.تو فرماتا ہے ثُمَّ السَّبِیْلَ یَسَّرَہٗ بظاہر انسان کے سامنے قربانی ایک بہت بڑا وسیع میدان ہے مگر اس کے ساتھ ہی فطرتِ انسانی میں ہم نے یہ مادہ رکھ دیا ہے کہ جب وہ عمل کرنا شروع کر دے تو بجائے اس کے کہ کام بوجھل محسوس ہو وہ اُسے آسان معلوم ہونے لگتا ہے اور اس کی طرف اُسے دلی رغبت پیدا ہو جاتی ہے چنانچہ ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی اور دوسری کے بعد تیسری نیکی میں وہ حصہ لینا شروع کر دیتا ہے.اگر عادت نہ ہوتی تو ایک نیکی کا کام بھی سرانجام دینا اس کے لئے مشکل ہوتا مگر چونکہ رفتہ رفتہ کاموں کی عادت ہوتی چلی جاتی ہے اس لئے انسان کاموں سے گھبراتا نہیں بلکہ اُن میں ایک لذّت اور سُرور محسوس کرتا ہے.پہلے وہ نماز پڑھتا ہے تو اُسے نماز کی عادت ہو جاتی ہے پھر روزے رکھتا ہے تو اُسے روزوں کی عادت ہو جاتی ہے.پھر صدقہ وخیرات میں حصہ لیتا ہے تو اُسے صدقہ و خیرات کی عادت ہو جاتی ہے اس طرح وہ ایک ایک نیکی کو فتح کرتا چلا جاتا ہے اور آگے بڑھنا اس کے لئے بالکل آسان ہو جاتا ہے.ثُمَّ اَمَاتَهٗ فَاَقْبَرَهٗۙ۰۰۲۲ پھر (عمر طبعی کے بعد) اُسے ماردیا پھر اُسے (موعود) قبر میں رکھا.٭ تفسیر.فرماتا ہے اس کے بعد ہم نے اُس کو وفات دی یعنی ہمارا طریق یہ ہے کہ اس کے بعد ہم اُس کو وفات دے دیتے ہیں.یہاں خدا تعالیٰ نے موت کو اپنے احسان کے طور پر پیش کیا ہے چنانچہ دیکھ لو اِن آیات میں ہر جگہ خدا تعالیٰ نے اپنے احسانات کا ہی ذکر کیا ہے فرماتا ہے مِنْ اَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهٗ.مِنْ نُّطْفَةٍ١ؕ خَلَقَهٗ فَقَدَّرَهٗ.ثُمَّ السَّبِيْلَ يَسَّرَهٗ.یہ سب احسانات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے شمار کرائے ہیں.اِسی ذیل میں فرماتا ہے ثُمَّ اَمَاتَہٗ فَاَقْبَرَہٗ.پس اماتت کو بھی یہاں احسان کے طور پر پیش کیا گیا ہے.فرماتا ہے جب انسان نیکیوں میں حصہ لیتا اور مسلسل حصہ لیتا چلا جاتا ہے تو آخر ایک وقت ایسا آتا ہے جب ہم کہتے ہیں اب تم نے بڑی محنت اُٹھا لی آئو ہم تم کو پنشن دیتے ہیں.گویا موت کیا ہے ایک پنشن ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے.دنیا میں لوگوں کو پنشن ملتی ہے تو وہ گورنمنٹ کے ممنون ہوتے ہیں مگر فرماتا ہے یہ عجیب نادان ہیں کہ ہم ان کو پنشن دیتے ہیں تو لوگ رونا شروع کر ٭نوٹ.اس جگہ قائدہ بیان ہوا ہے اور اس لحاظ سے ترجمہ میں پیدا کرتا ہے.اندازہ مقرر کرتاہے.آسان بناتا ہے.مار دیتا ہے وغیرہ کے الفاظ آنے چاہئیں لیکن چونکہ یہ الفاظ ترجمہ سے دور چلے جاتے تھے ہم نے ماضی کی جگہ ماضی ہی کے الفاظ رکھے ہیں لیکن مفہوم یہی ہے کہ انسان کی حالت ایسی ہوتی ہے اور خدا تعالیٰ کا سلوک اُس سے اس اس طرح کا ہوتا ہے پھر بھی وہ سمجھتا نہیں.
Page 269
دیتے ہیں.ثُمَّ اَمَاتَہٗ فَاَقْبَرَہٗ کے معنے فَاَقْبَرَہٗ جب انسان کو ہم موت دیتے ہیں تو اس کے بعد اُسے قبر میں داخل کرتے ہیں.اَقْبَرَہٗ کے معنے ہیں جَعَلَ لَہٗ قَبْرًا یُدْفَنُ فِیْہِ (اقرب) کہ اُس کے لئے ایک قبر مقرر کی جس میں وہ دفن کیا جاتا ہے اور یہ بھی اس کے معنے ہو سکتے ہیں کہ جَعٔلَہٗ مِمَّنْ یُقْبَرُ اُسے اُن لوگوں میں سے بنایا جن کے لئے قبر میں داخل ہونا مقدّر ہے اور اَقْبَرَ الْقَوْمَ کے یہ معنے بھی ہوتے ہیں کہ اَمَرَ اَنْ یُّقْبَرَ قَتِیْلُھُمْ (اقرب) اُس نے حکم دیا کہ اُن کےمقتولوں کو قبروں میں دفن کیا جائے.پس اَقْبَرَہٗ کے معنے ہوئے قبر میں اس کو داخل کیا یا قبر میں داخل ہونے کا حکم دیا یااُس کیلئے قبر میں داخل ہونے کا نظام جاری کیا.گویا یا تو اس کے یہ معنے ہوںگے کہ جَعَلَ لَہٗ قَبْرًا یُدْفَنُ فِیْہِ اور یااس کے معنے ہوں گے جَعَلَہٗ مِمَّنْ یُقْبَرُ کہ ہم نے اس کو ایسا بنایا کہ اس کو قبر میں ضرور داخل ہونا پڑتا ہے.اب اگر فَاَقْبَرَہٗ کے معنے یہ لئے جائیںکہ جَعَلَ لَہٗ قَبْرًا یُدْفَنُ فِیْہِ یعنی ہر انسان قبر میں داخل کیا جاتا ہے تو یہ معنے اس لحاظ سے یہاں چسپاں نہیں ہوں گے کیونکہ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو قبروں میں دفن نہیں ہوتے.اور اگر وہ معنے لئے جائیں جو اَمَرَ اَنْ یُّقْبَرَ قَتِیْلُھُمْ سے ظاہر ہیں تو وہ بھی یہاں چسپاں نہیں ہو سکتے.پس میرے نزدیک اَقْبَرَہٗ کے معنے اس جگہ یہی مناسب ہیں کہ جَعَلَہٗ مِمَّنْ یُّقْبَرُ یعنی ہم نے اس کو ایسا بنایا ہے کہ وہ قبر میں داخل کیا جاتا ہے.درحقیقت یہ ایک دلیل ہے جو پچھلی دلیل کے ایک حصہ اور ٹکڑہ کے طور پر اس جگہ بیان ہوئی ہے.اگر اَقْبَرَہٗ کے معنے خالی مٹی میں دفن کئے جانے کے ہوں تو یہ الفاظ دلیل کا حصہ نہیں بن سکتے.ثُمَّ اَمَاتَهٗ فَاَقْبَرَهٗمیں بعث بعد الموت کی طرف اشارہ وہ معنے جو عام طور پر ہماری طرف سے اس آیت کے کئے جاتے ہیں کہ اس آیت میں اُس قبر کا ذکر ہے جو عالمِ برزخ میں ہر انسان کو ملتی ہے وہ بھی درست ہیں مگر دشمن کہہ سکتا ہے کہ یہ ایک ڈھکوسلہ ہے ہمیں تو نظر نہیں آتا کہ اگلے جہان میں ہر مرنے والے کو قبر میں داخل کیا جاتا ہے اس لئے ہم تمہاری اس بے دلیل بات کو کس طرح مان سکتے ہیں اور میرے نزدیک جبکہ یہ ایک دلیل ہے جو گزشتہ دلیل کے جزو کے طور پر بیان ہوئی ہے تو بہرحال اَقْبَرَہٗ کا کوئی حصّہ دنیا میں بھی نظر آنا چاہیے.جو اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ہم اس کے معنے یہ کریں کہ جَعَلَہٗ مِمَّنْ یُّقْبَرُ یعنی انسانی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے یہ مادہ رکھ دیا ہے کہ وہ اپنے مردے کو قبر میں داخل کرے.اگر بعض لوگ اپنے مُردوں کو جلادیتے ہیں تو درحقیقت وہ بھی اسی لئے جلاتے ہیں کہ وہ پسند نہیں کرتے کہ اُن کے مُردے سڑتے گلتے رہیں اسی لئے وہ ان کو جلا کر راکھ کر دیتے ہیں.جو لوگ اپنے مُردے جانوروں کو کھلا دیتے ہیں وہ بھی اسی لئے کہ اُن کے نزدیک مردہ کا احترام یہ تقاضا کرتا
Page 270
ہے کہ ایسا کیا جائے.گویا مُردوں کی عزت اور اُن کا احترام کرنا انسانی فطرت میں داخل ہے اور یہی معنے فَاَقْبَرَہٗ کے ہیں کہ کوئی انسان اپنے مُردے کی ہتک برداشت نہیں کر سکتا باوجود اس کے کہ وہ ایک بے جان لاشہ ہوتا ہے فطرتِ انسانی اس بات کو برداشت نہیں کر سکتی کہ اُسے یونہی پھینک دیا جائے بلکہ ہر انسان خواہ وُہ کسی مذہب و ملّت سے تعلق رکھتا ہو اُس کا مناسب اعزاز کرے گا اور اپنے اپنے رنگ میں جو سلوک مناسب ہو گا اُس سے کرے گا.اور یہی وہ بات ہے جس میں انسان دوسرے جانداروں سے ممتاز ہے ورنہ اگر کھانے کو لو.تو انسان بھی کھاتا ہے اور جانور بھی کھاتا ہے.سونے کو لو تو انسان بھی سوتا ہے اور جانور بھی سوتا ہے مرنے کو لو تو انسان بھی مرتا ہے اور جانوربھی مرتا ہے.آگے یہ فرق ہو جاتا ہے کہ جانوروں میں یہ مادہ نہیں کہ وہ دوسرے جانوروں کی لاشوں کو دفنائیں لیکن کوئی انسان اپنے مردوں کو ایسی طرز پر نہیں رکھتا جس سے ان کے اعزاز میں فرق آئے.یہ مردے کا اعزاز اور اُس کا احترام جو انسانی فطرت میں داخل ہے بتاتا ہے کہ انسانی زندگی موت پر ختم نہیں ہو جاتی.اگر انسان کی زندگی اُس کی موت پر ختم ہے تو پھر اُس کے جسم کا احترام کون سا رہا یا اُس کے اعزاز کی ضرورت ہی کیا ہے اس صورت میں بیشک اُسے میدان میں پھینک دیا جائے کوئی حرج نہیں ہو گا.لیکن فطرتِ انسانی میں اس مادہ کا ہونا کہ مُردے کی عزت کی جائے اور اس کی عظمت میں کوئی فرق نہ آئے اس بات کی دلیل ہے کہ زندگی موت کے ساتھ ختم نہیں ہو جاتی.فرماتا ہے ہم تمہارے سامنے اس فطری دلیل کو پیش کرتے ہیں.تم اپنے مردہ کی لاش کو تحقیر کے ساتھ پھینکتے نہیں بلکہ اس کا مناسب احترام کرنا ضروری سمجھتے ہو.اگر اس کی آئندہ زندگی کا کوئی امکان نہیں تو تمہارے دل میں یہ خیال کیوں پیدا ہوتا ہے کہ مردے کا مناسب احترام کیا جائے.خواہ تم اپنے مُردوں کو بجلی سے جلا دو خواہ لکڑیوں کے انبار میں رکھ کر آگ لگا دو.خواہ خاص مقام پر رکھ کر سدھائی ہوئی چیلوں اور گِدھوں کو کھلا دو.بہرحال تم اپنے مُردوں سے وہ معاملہ نہیں کرتے جو جانور کرتے ہیں ایک کُتّا مر جاتا ہے تو دوسرے کُتوں کو خیال بھی نہیں آتا کہ اس کے ساتھ کوئی خاص سلوک کریں وہ اُسی طرح پڑا رہتا ہے یہاں تک کہ گل سڑ جاتا ہے.اسی طرح اگر انسانی زندگی اُس کی موت پر ختم تھی تو پھر چاہیے تھا لوگ اپنے مردوں کو یونہی پھینک دیتے مگر وہ ایسا نہیں کرتے بلکہ اپنے اپنے رنگ میں اس کا مناسب اعزاز کرتے ہیں پس فرماتا ہے ثُمَّ اَمَاتَہٗ فَاَقْبَرَہٗ ہم انسان کوموت دیتے ہیں.اور پھر اُس کے رشتہ داروں کے دلوں میں ایسی حس پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ اس کی لاش کو یوں ہی نہیں پھینک دیتے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں اگر ہم نے ایسا کیا تو مردہ کی عزت اور احترام میں فرق آئے گا.یہ دلیلِ فطرت پیش کر کے اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ جب مرنے کے بعد بھی تم عزت کے قائل ہو اور لاش کی عزت کرنا اپنے لئے ضروری سمجھتے ہو تو اس سے معلوم ہوا
Page 271
کہ مرنے کے بعد کی زندگی کا تمہارے دلوں میں بھی احساس موجود ہے گو یہ احساس ادنیٰ ہے مگر بہرحال یہ ادنیٰ احساس تمہاری روح کو اس اہم امر کی طرف متوجہ کرنے کے لئے کافی ہے کہ آخر وجہ کیا ہے کہ تمہارے دلوں میں مردہ کے احترام کا جذبہ پایا جاتا ہے.تمہارے دلوں میں اس جزبہ کا نمایاں طور پر پایا جانا اور دنیا میں کسی انسان کا بھی اپنے مردہ کی لاش کی ہتک گوارا نہ کر سکنا اس بات کا ثبوت ہے کہ زندگی موت کے ساتھ ختم نہیں ہو جاتی بلکہ کوئی اور حیات ہے جس کا اس موت سے آغاز ہوتا ہے اور انسان نہیں چاہتا کہ اس زندگی کے کوچہ میں داخل کرتے وقت محض اس خیال سے کہ یہ جسم تو مُردہ ہو چکا ہے اس کی عزت میں کوئی فرق آنے دے.ثُمَّ اِذَا شَآءَ اَنْشَرَهٗؕ۰۰۲۳ پھر جب چاہے گا اُسے دوبارہ اٹھا کھڑا کرے گا.حَلّ لُغَات.اَنْشَرَاَنْشَرَاللّٰہُ الْمَیِّتَ کے معنے ہوتے ہیں اَحْیَاہَ.اللہ تعالیٰ نے مردے کو زندہ کیا (اقرب) پس اِذَا شَآءَ اَنْشَرَہٗ کے معنے ہوں گے جب وہ چاہے گا اُسے زندہ کرے گا.تفسیر.فرماتا ہے کہ تم کو ان ساری باتوں سے نتیجہ نکال لینا چاہیے کہ جب خدا چاہے گا تم کو دوبارہ زندہ کر دے گا.ورنہ یہ تمام سلسلۂ پیدائش ہی لغو اور بے معنی قرار دینا پڑتا ہے آخر یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا بڑا کارخانہ جاری کرے اور پھر اس کے اندر کوئی غرض اور حکمت کام نہ کر رہی ہو.وہ انسان کو پیدا کرتا ہے ایک ایسی چیز سے جو نہایت ہی ذلیل ہے پھر ادنیٰ حالت سے ترقی دیتے دیتے اُسے اعلیٰ درجہ کے مقامات تک پہنچا دیتا ہے.اُس کے اندر ایسی قوتیں رکھتا ہے جو غیر محدود ہیں اور جوں جوں ترقی کے سامان ظاہر ہوتے چلے جاتے ہیں اُس کے مقابلہ میں اُس کی اندرونی قوتیں بھی رُونما ہونی شروع ہو جاتی ہیں پھر نہ صرف انسان کے اندر اس نے مختلف قسم کی قوتیں پیدا کیں بلکہ عادت کے ذریعہ وہ اُس کے کاموں میں بشاشت پیدا کر دیتا ہے اور جب اسی طرح ترقی کرتے کرتے انسان اپنے کمال کو پہنچ جاتا ہے تو تم یہ خیال کرتے ہو کہ اس کے بعد روح کو فنا کر دیا جاتا ہے حالانکہ اتنے بڑے کام کے بعد انعام ملنے کا حق ہوتا ہے نہ یہ کہ انعام تو کوئی نہ دیا جائے اور روح کو ابدی طور پر فنا کر دیا جائے.پھر جب انسان مر جاتا ہے تو تمہاری فطرت میں اللہ تعالیٰ نے یہ مادہ پیدا کیا ہوا ہوتا ہے کہ تم اپنے مردہ کی عزت کرو چنانچہ تم اپنے اپنے طریق کے مطابق احترام کے ساتھ اُسے اپنے گھر سے جُدا کرتے ہو اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ
Page 272
مرنے کے بعد بھی تم کسی عزت کے قائل ہو اور تمہارا یہ فعل اس بات پر گواہ ہے کہ زندگی موت پر ختم نہیں ہو جاتی بلکہ ثُمَّ اِذَا شَآءَ اَنْشَرَهٗ ایک اور حیات انسان کا انتظار کر رہی ہوتی ہے.اور وہ جب چاہے گا انسان کو زندہ کر دے گا.مگر یہ عجیب بات ہے کہ تم اور تو ساری باتیں مانتے چلے آتے ہو مگر یہاں آکر انکار کر دیتے ہو.گویا تم تسلیم کرتے ہو کہ انسان کی پیدائش بغیر کسی حکمت کے نہیں ہوئی.اس کا ادنیٰ حالت سے ترقی کر کے اعلیٰ درجہ تک کی حالت تک پہنچنا.اس کے اندر ترقی کی وسیع قابلیتوں کا رکھا جانا.اس کے سامنے ترقیات کا ایک وسیع میدان ہونا اور پھر اُن ترقیات کے مطابق انسانی قوتوں کا اُبھر آنا اور پھر عادت کے ذریعہ اس کے اندر بشاشت کا پیدا ہونا اور پھر جب وہ مر جائے تو تمہارا اپنے مردہ کی لاش کا احترام کرنا یہ سب امور اس بات کی ایک کھلی دلیل ہیں کہ مرنے کے بعد بھی کوئی زندگی ہے.مگر تمہاری عجیب حالت ہے کہ تم اور تو سب باتوں کو مانتے چلے آتے ہو مگر ان باتوں کا جو طبعی نتیجہ ہے اُس کو تسلیم کرنے سے نشوز کرتے ہو.كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَاۤ اَمَرَهٗؕ۰۰۲۴ (ایسا) ہر گز نہیں (جو تم سمجھتے ہو) (دیکھتے نہیں کہ) ابھی تک جو اسے حکم ملا تھا اُس نے اُسے پورا نہیں کیا.تفسیر.کَلَّا لَمَّا یَقْضِ مَآ اَمَرَہٗ سے مراد فرماتا ہے کَلَّا ہر گز نہیں لَمَّا یَقْضِ مَآاَمَرَہٗ اُس نے اب تک وہ کام نہیں کیا جس کا اُسے حکم دیا گیا تھا.لَمَّا یَقْضِ مَآ اَمَرَہٗ میں اسی طرف اشارہ ہے جس طرف مَایُدْرِیْکَ لَعَلَّہٗ یَزَّکّٰٓی میں اشارہ کیا گیا تھا اور جس کا قُتِلَ الْاِنْسَانُ مَآ اَکْفَرَہٗ میں بھی ذکر تھا.کہ انسان کے لئے موقع تھا کہ وہ خدا تعالیٰ کے قرب میں بڑھے اور اپنی عاقبت کو سنوار لے مگر اب تک اس نے اپنے اس فرض کو ادا نہیں کیا.اُس کے لئے روحانی ترقیات حاصل کرنے کا بہت بڑا موقع تھا اس کے لئے اللہ تعالیٰ کے قرب کا میدان کُھلا تھا مگر افسوس کہ اس نے اپنے اس فرض کو کماحقہٗ اب تک سرانجام نہیں دیا.یہی وہ چیز ہے جس پر میںآج کل بار بار زور دے رہا ہوں اور جماعت کو توجہ دلا رہا ہوں کہ وہ آئندہ نسلوں تک اِس امانتِ روحانی کو پہنچانے کے لئے اس قدر تن دہی اور اس قدر جانکاہی سے کام لے کہ شیطان ہمیشہ کے لئے مایوس ہو جائے اور کفر کے غلبہ کا دنیا میں کوئی امکان نہ رہے.آج تک کسی اُمت نے بھی اپنی نسل کو شیطانی حملوں سے محفوظ رکھنے پر زور نہیں دیا اگر ہماری جماعت اس فرض کو سرانجام دے لے تو یقیناً یہ ایک بے مثال کام ہو گا اور اس کی نظیر اَور کسی اُمّت میں نہیں مل سکے
Page 273
گی.اللہ تعالیٰ اسی نکتہ کی طرف توجہ دلاتا ہے اور افسوس کے ساتھ فرماتا ہے کہ لَمَّا یَقْضِ مَآ اَمَرَہٗ ہم نے انسان کو جو حکم دیا تھا اس کو اب تک اُس نے ادا نہیں کیا.فرداً فرداً لوگوں نے اپنی اصلاح کی بہت کوششیں کی ہیں مگر قوم کی قوم کو اُبھار کر ترقی کے میدان میں اس طرح بڑھاتے چلے جانا کہ پھر اس کے گرنے کا کوئی امکان نہ رہے اور شیطان اُس کو ورغلانے سے مایوس ہو جائے یہ کام اَیسا ہے جس کی طرف ابھی تک توجہ نہیں کی گئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت پر چونکہ مُختلف دَور آتے ہیں اس لئے ممکن ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کے دَوروں میں سے کوئی دَور ایسا بھی آجائے جس میں اس فرض کی ادائیگی ہو سکے جس کا کَلَّا لَمَّا یَقْضِ مَآ اَمَرَہٗ میں ذکر کیا گیا ہے.اب تک الگ الگ کوششیں کر کے اُن کے نتائج کو دیکھا جا چکا ہے صحابہؓ نے تیس سال کوشش کی مگر پھر اُن کی نسلوں میں کمزوری پیدا ہو گئی اور نیکی کا تسلسل جاتا رہا.اب ہمارے لئے موقع ہے کہ ہم اس کام کو سرانجام دینے کے کوشش کریں تاکہ قومی طور پر اسلام دنیا میں اس طرح قائم ہو جائے کہ پھر اس کے گرنے کا کوئی امکان ہی نہ رہے.یہ کام ایسا ہے جو پہلے کبھی نہیں ہوا.انفرادی رنگ میں بے شک بہت کوششیں ہوئیں مگر قومی طور پر اسلام کی برتری کی ایسی کوشش نہیں کی گئی کہ نیکی کا تسلسل قائم رہتا اور اسلام کے گرنے کا کبھی خطرہ پیدا نہ ہوتا.پس کَلَّا لَمَّا یَقْضِ مَآ اَمَرَہٗ میں اسی طرف توجہ دلائی گئی ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب تک انسان نے وہ بات نہیں کی جس کا ہم نے اسے حکم دیا تھا.كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَاۤ اَمَرَهٗمیں موعود کل ادیان کی بعثت کی ضرورت کی طرف اشارہ اس کے ایک اور معنے بھی ہو سکتے ہیں اور وہ یہ کہ انسانی قوتیں جس مقامِ عظیم کو حاصل کر سکتی ہیں اب تک انسان نے اُس مقام کو حاصل نہیں کیا پس تم کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ ابھی موعود کل ادیان آنا باقی ہے جس سے انسانی ترقی کا آخری مقام وابستہ ہے او ر بجائے اس کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو حقارت سے دیکھا جائے اس کی طرف سنجیدگی سے توجہ کرنی چاہیے.فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ اِلٰى طَعَامِهٖۤۙ۰۰۲۵اَنَّا صَبَبْنَا الْمَآءَ پس چاہیے کہ انسان اپنے کھانے کی طرف دیکھے (اور دیکھے) کہ ہم نے (بادلوں سے) پانی کو خوب برسایا ہے.صَبًّاۙ۰۰۲۶ثُمَّ شَقَقْنَا الْاَرْضَ شَقًّاۙ۰۰۲۷فَاَنْۢبَتْنَا فِيْهَا حَبًّاۙ۰۰۲۸ پھر زمین کو خوب پھاڑا ہے پھر اس میں دانہ اگایا ہے.
Page 274
وَّ عِنَبًا وَّ قَضْبًاۙ۰۰۲۹وَّ زَيْتُوْنًا وَّ نَخْلًاۙ۰۰۳۰ اور( اسی طرح) انگور اور ترکاریاں (اور سبز چارہ) اور زیتون اور کھجوریں وَّ حَدَآىِٕقَ غُلْبًاۙ۰۰۳۱وَّ فَاكِهَةً وَّ اَبًّاۙ۰۰۳۲مَّتَاعًا لَّكُمْ وَ اور گھنے باغات اور میوے اور خشک گھانس (اور جھاڑیاں بھی) ( یہ سب) تمہارے اور تمہارے لِاَنْعَامِكُمْؕ۰۰۳۳ جانوروں کے فائدہ کے لئے (کیا گیا ہے).تفسیر.چاہیے کہ انسان اپنے کھانے کی طرف دیکھے اور غور کرے کہ ہم اس کی جسمانی پرورش کے لئے کیا کچھ کرتے ہیں.ہم نے اس کے لئے آسمان سے پانی برسایا پھر ہم نے زمین کو اس کی خاطر پھاڑا.پھر ہم نے اُس میں سے دانے نکالے اور انگور پیدا کئے اور قضب پیدا کیا.لُغت میں لکھا ہے کہ اَلْقَضْبُ کُلُّ شَجَرَۃٍ طَالَتْ وَسَبَطَتْ اَغْصَانُھَا وَالْقَتُّ.وَالْقَتُّ: اَلْفِصْفِصَۃُ الْیَابِسُ وَالْفِصْفِصَۃُنَبَاتٌ تَعْلُفُہُ الدَّوَابُ وَھِیَ تُسَمَّی بِذَالِکَ مَادَامَتْ رَطْبَۃً فَاِذَاجَفَّتْ زَالَ عَنْھَا اِسْمُ الْفِصْفِصَۃِ وَسُمِّیَتْ بِالقَتِّ حَبُّھَا نَحْوُ الْکَرْسَنَّۃِ لٰکِنْ فِیْہِ طُوْلٌ (اقرب)قضبؔ کہتے ہیں ہر ایسے درخت کو جو اونچا بھی ہو اور اس کی شاخیں بھی اردگرد پھیلی ہوئی ہوں.جانور اس کو شوق سے کھاتے ہیں خصوصًا اونٹ ایسے درخت کی طرف بہت رغبت سے جاتا ہے.اسی طرح قتؔ کو بھی قضب کہتے ہیں اور قَتّ فِصْفِصَۃ کو کہتے ہیں یہ ایک روئیدگی ہے جس کو جانور کھاتے ہیں جب تک تازہ رہے فِصْفِصَۃ کہتے ہیں اور جب سُوکھ جائے تو اس کو قَتّ کہتے ہیں.اس کا دانہ کرسنّہ کی طرح ہوتا ہے مگر اس سے کسی قدر لمبا ہوتا ہے (کرسنّہ گندنے کو کہتے ہیں جسے پنجابی میں بھوکاٹ کہا جاتا ہے) پھر فرماتا ہے ہم نے زیتون نکالا اور کھجوریں پیدا کیں اور باغات پیدا کئے منڈیروں والے.ایسے باغات غُلْبًا جو بڑے گھنے ہیں.غُلب اُس چیز کو کہتے ہیں جو مُلْتَفٌّ یعنی لپٹی ہوئی ہو.پس حَدَائِقَ غُلْبًا کے معنے یہ ہوئے کہ ہم نے ایسے باغات پیدا کئے ہیں جن کی شاخیں ایک دوسرے سے لپٹی ہوئی ہیں یعنی بڑے گھنے ہیں.اسی طرح ہم نے میوے پیدا کئے ہیں اور پھر چارہ بھی پیدا کیا ہے.اَبٌّ اُن تمام چیزوں کو کہتے ہیں جن کو انسان نہیں کھاتا اور نہ اُن کو بوتا ہے.قدرتًا زمین میں سے اُگ آتی ہیں اور جانور اُن کو کھاتے ہیں چنانچہ لکھا ہے اَلْاَبُّ کُلُّ مَا یُنْبِتَ الْاَرْضُ مِمَّا لَا
Page 275
یَاْکُلُہٗ النَّاسُ وَلَا یَزْرَعُوْنَہٗ (فتح البیان زیر آیت ھذا) سورۃ النازعات اور سورۃ عبس کے ایک مضمون کی مشابہت مَتَاعًا لَّکُمْ وَلِاَنْعَامِکُمْ.ان تمام چیزوں کو ہم نے تمہارے لئے فائدہ کا موجب بنایا ہے اور تمہارے اَنْعام کے لئے بھی.قرآن کریم کے بعض مقامات ایسے ہیں جو لفظی رنگ میں ایک دوسرے سے مشابہت رکھتے ہیں اسی قسم کی مشابہت اس جگہ بھی پائی جاتی ہے چنانچہ یہی مضمون سورۂ نازعات میں بھی تھا مگر اور رنگ میں.وہاں فرمایا تھا ءَاَنْتُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمِ السَّمَآءُ١ؕ بَنٰىهَا.رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوّٰىهَا.وَ اَغْطَشَ لَيْلَهَا وَ اَخْرَجَ ضُحٰىهَا.وَ الْاَرْضَ بَعْدَ ذٰلِكَ دَحٰىهَا.اَخْرَجَ مِنْهَا مَآءَهَا وَ مَرْعٰىهَا.وَ الْجِبَالَ اَرْسٰىهَا.مَتَاعًا لَّكُمْ وَ لِاَنْعَامِكُمْ اس سورۃ میں بھی اسی طرح کی چیزیں گنائی ہیں کہ فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ اِلٰى طَعَامِهٖۤ.اَنَّا صَبَبْنَا الْمَآءَ صَبًّا.ثُمَّ شَقَقْنَا الْاَرْضَ شَقًّا.فَاَنْۢبَتْنَا فِيْهَا حَبًّا.وَّ عِنَبًا وَّ قَضْبًا.وَّ زَيْتُوْنًا وَّ نَخْلًا.وَّ حَدَآىِٕقَ غُلْبًا.وَّ فَاكِهَةً وَّ اَبًّا.مَّتَاعًا لَّكُمْ وَ لِاَنْعَامِكُمْ فرق صر ف یہ ہے کہ سورۂ نازعات میں زیادہ تر آسمانی چیزوں کو پیش کیا گیا تھا.گو زمینی چیزوں کا بھی اس میں ذکر تھا مگر اصل مقصد نظام سماوی کو پیش کرنا تھا لیکن اس جگہ نظام ارضی کو خصوصیت کے ساتھ پیش کیا گیا ہے.گویا پچھلی سورۃ میں اُس وسیع نظام کی طرف اشارہ کیا گیا تھا جو آسمان اور زمین دونوں پر حاوی ہے مگر اس سورۃ میں اُس مخصوص نظام کی طرف اشارہ ہے جو زمین میں روئیدگی پیدا کرنے کا موجب ہوتا ہے.وہاں خدا تعالیٰ نے اس طرف اشارہ کیا تھا کہ جس طرح زمین پر آسمان کا وجود ضروری ہے اور بغیر آسمانی نظام کے زمینی نظام قائم نہیں ہو سکتا اسی طرح تمہارے لئے بھی ایک روحانی بلندی کی ضرورت ہے.اگر تم یہ خیال کرو کہ اس رُوحانی بلندی کے بغیر تم نظام ارضی کو قائم کر سکو گے تو یہ تمہاری غلطی ہو گی جس طرح آسمان کے بغیر زمین کا وجود عبث ہے اسی طرح روحانی نظام کے بغیر جسمانی نظام عبث اور بےکار ہوتا ہے یہاں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ انسانی فطرتوں میں سے بعض ایسی ہیں جو قرآن کریم سے مناسبت رکھتی ہیں اور بعض ایسی ہیں جو قرآن کریم سے کوئی مناسبت نہیں رکھتیں.وہ فطرتیں جو قرآن کریم سے مناسبت رکھتی ہیں وہ آپ ہی آپ اس طرف آجائیں گی اور جو اس سے مناسبت نہیں رکھتیں وہ اس طرف توجہ بھی نہیں کریں گی.پس سورۂ نازعات میں اور مضمون تھا اور اس سورۃ میں اور مضمون ہے.وہاں آسمان کا ذکر کلام الٰہی کے نزول کی ضرورت پر روشنی ڈالنے کے لئے پیش کیا گیا تھا اَور یہاں یہ بتایا ہے کہ بعض طبائع قرآنی تعلیم سےمناسبت رکھتی ہیں اور بعض نہیں رکھتی وہ طبائع جو اس تعلیم سے مناسبت رکھتی ہیں وہ دوڑتی ہوئی اس طرف آجائیں گی اور جن کے قلب میں اس سے کوئی مناسبت نہیں ہو گی وہ اس سے دُور رہیں گی جیسے زمین کو دیکھ لو کہ اس
Page 276
میں سے دانے بھی اُگتے ہیں.انگور بھی پیدا ہوتے ہیں.درخت بھی پیدا ہوتے ہیں.زیتون بھی پیدا ہوتا ہے.کھجوریں بھی پیدا ہوتی ہیں.باغات بھی پیدا ہوتے ہیں.میوے بھی پیدا ہوتے ہیں.اور چارہ بھی پیدا ہوتا ہے.ان میں سے کوئی چیز ایسی ہے جسے انسان مُنہ مارتا ہے اور کوئی چیز ایسی ہے جسے جانور مُنہ مارتا ہے.یہی انسانی طبائع کا حال ہے.جو قرآن کے مناسب حال ہیں وہ اس طرف آجائیں گی اور جو کفر کے مناسب حال ہیں وہ اُس طرف چلی جائیں گی.گویا فطرتیں خود بخود بول اٹھیں گی اُن کے مناسب حال کون سی چیز ہے.جیسے انگور ہوں تو اُن کی طرف انسان جائے گا اونٹ نہیں جائے گا لیکن اگر کیکر کا درخت ہو تو اس کی طرف اونٹ جائے گا انسان نہیں جائے گا.تو فرماتا ہے انسان نے بیشک ابھی تک اس قرآن پر عمل نہیں کیا مگر وہ مجبور ہے جس دن قرآن کریم کی روئیدگیاں ظاہر ہوئیں اور اس کا حُسن دنیا میں چمکا تم دیکھ لو گے کہ مناسب حال فطرتیں اس کی طرف دوڑتی ہوئی آئیں گی.اب تو یہ لوگ تمہیں تھوڑے سے نظر آتے ہیں مگر پھر گروہ در گروہ اور جوق در جوق لوگ اس مذہب میں داخل ہونے شروع ہو جائیں گے.چنانچہ مثال دیتے ہوئے فرماتا ہے.تم دنیا میں دیکھ لو.کچھ دانےؔ.انگورؔ.زیتونؔ.کھجورؔ.باغاتؔ.اور میوےؔ ہوتے ہیں اور کچھ جھاڑیاں اورچارہ وغیرہ ہوتا ہے.تم اُن چیزوں کی طرف چلے جاتے ہو جو تمہارے مناسب حال ہیں اور جانور اُن چیزوں کی طرف چلے جاتے ہیں جو اُن کے مناسب حال ہیں.اسی طرح جو نیک فطرتیں ہیں وہ قرآن کی طرف آجائیں گی اور جو بد فطرتیں ہیں وہ کفر کی طرف چلی جائیں گی.یہ عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اُن چیزوں کا تو زیادہ ذکر کیا ہے جو انسانوں کے کھانے کے کام آتی ہیں مگر ان چیزوں کا کم ذکر کیا ہے جو جانوروں کے کھانے کے کام آتی ہیں چنانچہ چھ جگہ انسانوں کے کام آنے والی چیزوں کا ذکر کیا اور دو جگہ جانوروں کے کام آنے والی چیزوں کا.اس میں اِس طرف اشارہ ہے کہ قرآن زیادہ آدمی کھینچ لے گا اور کفر اپنی طرف کم آدمی کھینچے گا.چنانچہ جانور کے لئے تو صرف قُضِبٌ اور اَبٌ کا ذکر کیا مگر انسان کے لئے حَبًّا وَّعِنَبًا وَّقَضْبًاوَّزَیْتُوْنًا وَّنَخْلًا وَّحَدَآئِقَ غُلْبًا وَّ فَاکِھَۃً اتنی چیزوں کا ذکر کر دیا یہ بتانے کے لئے کہ قرآن کی طرف لوگوں کا رجوع زیادہ ہو گا اور کفر کی طرف کم.پس فرماتا ہے یہ سوال ہی غلط ہے کہ اسلام کا غلبہ کس طرح ہو گا.فطرتیں اپنی مناسب حال چیز کی طرف آپ ہی بھاگتی چلی آئیں گی وہ فطرتیں جو قرآن کریم کے مناسب حال ہیں وہ اس کی طرف آجائیںگی.جیسے حبؔ اور عنبؔ اور زیتونؔ اور نخلؔ اور حدائقؔ اور فاکھتہ کی طرف انسان جاتے ہیں اور جو فطرتیں کفر کے مناسب حال ہیں وہ اُس کی طرف چلی جائیںگی جیسے جانور قضب اور اَبّ کی طرف جاتے ہیں.انگوروں اور کھجوروں کی طرف نہیں جاتے.
Page 277
فَاِذَا جَآءَتِ الصَّآخَّةُٞ۰۰۳۴يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيْهِۙ۰۰۳۵ پھر (یہ بھی تو سوچو کہ) جب کان پھاڑنے والی (مصیبت) آئے گی جس دن کہ انسان اپنے بھائی سے (دُور) بھاگے وَ اُمِّهٖ وَ اَبِيْهِۙ۰۰۳۶وَ صَاحِبَتِهٖ وَ بَنِيْهِؕ۰۰۳۷لِكُلِّ امْرِئٍ گا اور (اسی طرح) اپنی ماں اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی اور بیٹوں سے (بھی) اس دن ہر ایک آدمی کی حالت مِّنْهُمْ يَوْمَىِٕذٍ شَاْنٌ يُّغْنِيْهِؕ۰۰۳۸ ایسی ہو گی کہ وہ اُسے اپنی (ہی) طرف اُلجھائے رکھے گی.حَلّ لُغَات.اَلصَّآخَۃُ: اَلصَّاخَۃُ صخَّ سے اسم فاعل کا مؤنث کاصیغہ ہے.اور صَخَّ الصَّوْتُ الْاُذُنَ کے معنے ہوتے ہیں اَصمَّھَا.اتنے زور کی آواز آئی کہ اُس نے کان پھاڑ دیا اور اُسے بہرہ کر دیا (اقرب) اَلصَّآخَۃُ کے معنے ہیں صَیْحَۃُ تُصِمُّ لِشِدَّتِھَا.ایسے زور کی آواز جو کانوں کو بہرہ کر دے نیز اس کے معنے ہیں اَلدَّاھِیَۃُ سخت مصیبت.(اقرب) تفسیر.فرماتا ہے جب وہ کان پھاڑنے والی آواز آجائے گی یَوْمَ یَفِرُّالْمَرْئُ مِنْ اَخِیْہِ جس دن کہ آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا وَاُمِّہٖ اور اپنی ماں سے بھاگے گا وَاَبِیْہِ اور اپنے باپ سے بھاگے گا وَصَاحِبَتِہٖ ا ور اپنی بیوی سے بھاگے گا وَبَنِیْہِ اور اپنے بیٹوں سے بھاگے گا.لِکُلِّ امْرِيءٍ مِّنْھُمْ یَوْمَئِذٍ شَاْنٌ یُّغْنِیْہِ.اُس دن انسان کے حالات ایسے ہوں گے کہ وہ گردوپیش کی طرف نہ دیکھ سکے گا اور دوسروں کی طرف وہ توجہ ہی نہ کرے گا.قیامت کے دن تو لوگوں کی ایسی حالت ہو گی ہی.الصَّآخَّةُسے مراد قرآن کی آواز صحابہؓ کے حالات پر غور کر کے دیکھو جس وقت قرآن کا نزول ہوا کس طرح دنیا نے اپنی آنکھوں سے اس نظارہ کا مشاہدہ کیا کہ باپ نے بیٹے کو چھوڑ دیا بیٹے نے باپ کو چھوڑ دیا.ماں بیٹی سے الگ ہو گئی اور بیٹی ماں سے الگ ہو گئی.بھائی بھائی سے جدا ہو گیا اور دوست دوست سے علیحدہ ہو گیا.یَوْمَ یُفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِیْہِ وَاُمِّہٖ وَاَبِیْہِ وَصَاحِبَتِہٖ وَبَنِیْہِ بھائی بھائی کو چھوڑ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگیا.خاوند اپنی بیوی کو چھوڑ کر اور بیوی اپنے خاوند کو چھوڑ کر.باپ اپنے بیٹے سے الگ ہو کر اور بیٹا اپنے باپ سے الگ ہو کر.ماں اپنی بیٹی کو چھوڑ کر اور بیٹی اپنی ماں سے علیحدہ ہو کر.دوست اپنے دوست کو چھوڑ کر اور رشتہ دار اپنے
Page 278
رشتہ دار سے علیحدہ ہو کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کے حلقۂ اطاعت میں آگئے اور انہوں نے کسی دنیوی محبت کی خدا اور اس کے رسول کی رضاء کے مقابلہ میں پروا نہ کی.لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَىِٕذٍ شَاْنٌ يُّغْنِيْهِ.اور پھر وہ اسلام اور قرآن کی محبت میں ایسے محو ہو گئے کہ وہ دُنیا اور اس کی دلچسپیوں کو بالکل بھول ہی گئے.يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ کا نظارہ صحابہ کرام میں تاریخ اسلام کے صفحات پر صحابہؓ کرام کی اس قربانی کی کتنی ہی واضح مثالیں موجود ہیں مگر میں اس جگہ صرف دو مثالیں بیان کر دیتا ہوں جن کا میں پہلے بھی کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں.ایک نوجوان جو اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا وہ مسلمان ہو گیا.اُس کے ماں باپ نے اُسے کئی قسم کی تکلیفیں دینی شروع کیں یہاں تک کہ اس کے برتن الگ کر دئے مگر وہ اسلام کو ترک کرنے پر آمادہ نہ ہوا آخر کچھ عرصہ کے بعد وہ مکّہ سے ہجرت کر کے چلا گیا.کچھ مدت گزرنے کے بعد وہ پھر مکّہ میں واپس آیا جس پر اُس کے ماں باپ اُسے بڑے شوق اور محبت سے ملے.انہوں نے سمجھا کہ یہ اسلام سے توبہ کر چکا ہے اور بیٹے نے یہ سمجھا کہ یہ میرے بعد اسلام کی دشمنی کو ترک کر چکے ہیں اور اس لئے مجھے محبت سے مل رہے ہیں اور اب اپنے افعال پر پچھتاتے ہیں.کچھ دیر کے بعد ماں باپ نے کہا بیٹا ہم تو تمہیں پہلے بھی یہی نصیحت کیا کر تے تھے کہ اس صابی کی طرف مت جائو.اُن کا اشارہ اس صابی کے لفظ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف تھا.گویا اس رنگ میں انہوں نے اپنی خیر خواہی جتانی شروع کر دی کہ ہم تو تمہیں پہلے ہی کہا کرتے تھے کہ اسلام میں داخل ہو کر تم نے بڑی غلطی کی.اب اچھا ہوا جو اسلام کو چھوڑ کر پھر ہم میں شامل ہو گئے ہو.اُس نوجوان نے جب یہ بات سُنی تو وہ اُسی وقت کھڑا ہو گیا اور کہا ماں!تم میری ماں ہو اور باپ! تم میرے باپ ہو مگر محمدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مجھے اور کوئی پیارا نہیں.میں نے یہ سمجھا تھا کہ تمہارے دل میں رحم پیدا ہو چکا ہے اور تم اپنے افعال پر پشیمان ہو لیکن میرا خیال غلط نکلا.اگر تمہارا میرے ساتھ ملنا اسی شرط سے وابستہ ہے کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دُوں تو یہ ناممکن بات ہے.محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی میری ماں ہیں.یہ کہہ کر وہ وہاں سے اٹھا اور پھر اُس نے مرتے دم تک اپنے ماں باپ کو نہیں دیکھا.پھر اس عورت کے واقعہ پر غور کرو جو مدینہ کی رہنے والی تھی جو جنگ اُحد میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر سُن کر دیوانہ وار اپنے گھر سے نکل کھڑی ہوئی تھی اور جب اُسے یکے بعد دیگرے بتایاگیا کہ تیرا باپ اس جنگ میں مارا گیا ہے.تیرا خاوند اس جنگ میں مارا گیا ہے تیرا بھائی اس جنگ میں مارا گیا ہے تو اُس نے کہا میں تم سے یہ نہیں پوچھتی کہ میرے باپ اور میرے خاوند اور میرے بھائی کا کیا حال ہے میں تم سے یہ پوچھتی ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے
Page 279
اور جب اس کو بتایا گیا کہ آپ تو خدا کے فضل سے بخیریت ہیں تو اُس کے مُنہ سے بے اختیار نکلا کہ اگر آپ خیریت سے ہیں تو پھر کوئی مصیبت ایسی نہیں ہو سکتی جو نا قابل برداشت ہو.(السیرۃ النبویۃ لابن ہشام غزوۃ احد) غرض يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيْهِ.وَ اُمِّهٖ وَ اَبِيْهِ کا نظارہ ہمیں صحابہ کرام میں نظر آتا ہے.اس کے بالقابل کفار میں بھی ایسا ہی جوش تھا کہ بھائی بھائی پر حملہ کرنے کے لئے تیار ہو جاتا اور باپ بیٹے کو قتل کرنے کے لئے دوڑتا.چنانچہ جب جنگ ہوتی تو اس میں بھائی بھائی کو مارنے کے لئے آگے بڑھتا تھا اور اپنے رشتہ داری تعلقات کی ذرا بھی پروا نہیں کرتا تھا یوں معلوم ہوتا تھا کہ وہ ایک جنس نہیں ہیں بلکہ دو الگ الگ جنسیں ہیں.مومن ہے تو وہ کہتا تھا میرا کافر سے کوئی واسطہ نہیں میرا وہی دوست ہے جو مومن ہے.اور کافر ہے تو وہ کہتا تھا میرا مومن سے کوئی واسطہ نہیں.میرا وہی دوست ہے جو کافر ہے.یہی وہ صَاخَّۃ کی علامت ہے جو سچے مذہب کی آمد پر ظاہر ہوا کرتی ہے اور جس کے بعد کسی قسم کی مداہنت یا کسی قسم کی منافقت برداشت نہیں کی جا سکتی.کفر اور ایمان میں ایک بیّن اور کُھلا کُھلا امتیاز ہو جاتا ہے.لیکن جھوٹے مذاہب کے درمیان یہ بات نہیں ہوتی.اسی طرح اُس قوم میں بھی یہ امتیازی علامت نہیں رہ سکتی.جو جھوٹے مذہب کا حصہ بن جائے جیسے غیر مبایعین ہیں کہ وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تعلیم کے خلاف غیر احمدیوں کے پیچھے نمازیں پڑھ لیں گے.اُن سے رشتہ داری تعلقات قائم کر لیں گے اور اس میں کسی قسم کی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کریں گے حالانکہ خدا کی آواز صاخّہ ہوتی ہے اور جب وہ بلند ہوتی ہے تو بھائی کو اپنے بھائی سے اور رشتہ دار کو اپنے رشتہ دار سے جُدا ہونا پڑتا ہے.وُجُوْهٌ يَّوْمَىِٕذٍ مُّسْفِرَةٌۙ۰۰۳۹ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌۚ۰۰۴۰ کچھ (لوگوں کے) چہرے اُس دن روشن ہوں گے ہنستے ہوئے خوش بخوش.حَلّ لُغَات.مُسْفِرَۃٌ مُسْفِرَۃٌکے معنے ہیں مُضِیْئَۃٌ مُشْرِقَۃٌ.روشن اور چمکنے والی.چنانچہ اَسْفَرَ الصُّبْحُ کے معنے ہوتے ہیں اَضَائَ وَاَشْرَقَ.صبح روشن ہو گئی اور اس کی سفیدی پھیل گئی.اور اَسْفَرَ وَجْہُہٗ کے معنے ہوتے ہیں.حَسُنَ وَاَشْرَقَ کہ اس کا چہرہ خوبصورت ہو گیا اور روشن ہو گیا (اقرب) پس فرماتا اُس دن کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو بڑے خوبصورت ہوں گے.بڑے روشن اور چمکدار ہوں گے.ضَاحِکَۃٌ ہنس رہےہوں گے.مُسْتَبْشِرَۃٌ.مُسْتَبْشَرَۃٌ اِسْتَبْشَرَ سے ہے اور اِسْتَبْشَرَ کے معنے خوش ہونے کے بھی ہوتے ہیں اور خوشخبری حاصل کرنے کے بھی ہوتے ہیں.(لسان) پس مُسْتَبْشِرَۃٌ کے معنے یہ ہیں کہ وہ بڑے خوش ہوں گے
Page 280
اور انہیں بڑی خوشخبریاں مل رہی ہوں گی.کہ ابھی اور فتح آنے والی ہے اور غلبہ ملنے والا ہے اور نصرت نازل ہونے والی ہے.تفسیر.فرماتا ہے مومن اور کافر چونکہ دو الگ الگ گروہ ہیں اس لئے ان سے ہمارا سلوک بھی الگ الگ ہو گا جو لوگ ہمارے احکام پر ایمان لائے ہیں ان کو ہم اپنے انعا مات سے حصہ دیں گے اور جنہوں نے انکار کیا ہے ان کو اپنے عذاب سے حصہ دیں گے.چنانچہ فرماتا ہے اس دن کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو روشن ہوںگے اور خوبصورت ہوں گے ہنس رہے ہوں گے اور خوش ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے بشارتیں حاصل کر رہے ہوں گے.جیسا کہ حل لغات میں بتایا گیا ہے مُسْتَبْشِرَۃٌ دو معنے رکھتا ہے خوش ہونے کے بھی اور خوشخبری حاصل کرنے والے کے بھی.تو مومنوں کو ہر دو امور حاصل ہوں گے.وَ وُجُوْهٌ يَّوْمَىِٕذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌۙ۰۰۴۱تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌؕ۰۰۴۲ اور کچھ (لوگوں کے) چہرے اُس دن ایسے ہوں گے کہ اُن پر غبار اُڑ رہی ہو گی.اُن پر سیاہی چھا رہی ہو گی حَلّ لُغَات.غَبَرَۃٌ غَبَرَۃٌکے معنے ہیں اَلْغُبَارُ یعنی غبار (اقرب) تَرْھَقُ تَرْھَقُ رَھِقَسے ہے اور رَھِقَ کے معنے ہوتے ہیں غَشِیَہٗ وَلَحِقَہٗ.اس کو جا پکڑا یا جا لیا (اقرب) پس تَرْھَقُھَا قَتَرَۃٌ کے یہ معنے ہوئے قترہ ان کو پکڑ لے گی یا قترہ اُن سے جا ملے گی اور قَتَرَۃٌ کے معنے ہوتے ہیں اَلْغَبَرَۃُ غبار اس کی جمع قَتَرٌ آتی ہے (اقرب) تفسیر.فرماتا ہے جس دن یہ افتراق پیدا ہو جائے گا کفر اور اسلام میں ایک بیّن امتیاز قائم ہو جائے گا.خدا تعالیٰ کا صور آسمان سے پھونکا جائے گا اور مومن ایک طرف ہو جائیں گے اور کافر دوسری طرف.کچھ لوگ ایمان کے باغ پر لٹّو ہو رہے ہوں گے اور کچھ لوگ کُفر کے گھاس پر مُنہ مار رہے ہوں گے اور اونٹ اور بکریاں درختوں کی طرف چلی جائیں گی اور انسان انگوروں اور کھجوروں کی طرف چلے جائیں گے یہ مضمون ہے جو اللہ تعالیٰ نے اِن آیات میں بیان کیا ہے.فرماتا ہے اُس دن کچھ چہرے ایسے ہوں گے جن پر غبار پڑا ہوا ہو گا.مطلب یہ ہوا کہ پہلے دن اُن کے منہ پر مٹی لگے گی اور پھر اُن کے سارے جسم کو ڈھانپ لے گی.جانور کو جب ذبح کرنے کے لئے لٹایا جاتا ہے تو پہلے اُس کے منہ کو مٹی لگتی ہے لیکن جب اُسے ذبح کیا جاتا ہے تو وہ تڑپتا ہے اور اس تڑپنے کی وجہ سے اُس
Page 281
کے سارے جسم پر مٹی لگ جاتی ہے.اسی طرف اِن آیات میں اشارہ کیا گیا ہے کہ ان کوذبح کرنے کے لئے پہلے ہم زمین پر لٹائیں گے جس سے اُن کے منہ پر مٹی لگے گی مگر جب انہیں ذبح کیا جائے گا اور یہ تڑپنا شروع کریں گے.تو پھر اُن کا سارا جسم مٹی سے ڈھانپا جائے گا گویا کفار کی کامل تباہی کی خبر دی گئی ہے.اُولٰٓىِٕكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُؒ۰۰۴۲ یہی وہ (لوگ)ہوں گے جو کافر اور بد کار ہیں.حَلّ لُغَات.کَفَرَۃٌاَلْکَفَرَۃُ کَافِرٌ کی جمع ہے جو کَفَرَ سے اسم فاعل ہے اور کَفَرَ کے معنے ہیں ضِدُّ اٰمَنَ وہ والا ایمان نہ لایا اور جب کَفَرَ نِعْمَۃَ اللّٰہِ کہیں تو معنے ہوں گے جَحَدَھَا وَسَتَرَھَا یعنی خدا کی نعمت کی ناقدری و ناشکری کی اور اس کا انکار کیا.اور جب کَفَرَ الشَّیْءَ کہیں تو معنے ہوں گے سَتَرَھَا کسی چیز کو چھپا دیا (اقرب) پس کَافِر کے معنے ہوں گے (۱)ایمان نہ لانے والے (۲)اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرنے والے (۳)کسی بات کو چھپانے والا.اقرب کا مصنّف لکھتا ہے کہ کَفَرَۃٌ عربی زبان میں عمومًاان لوگوں کے لئے بولتے ہیں جو خدا کی نعمتوں کی ناقدری کریں.(اقرب) اَلْفَجَرَۃُ.اَلْفَجَرَۃٌ اَلْفَاجِرُ کی جمع ہے جو فَجَرَ (یَفْجُرُ) سے اسم فاعل ہے.فَجَرَ الرَّجْلُ(فُجُوْرًا) کے معنے ہیں اِنْبَعَثَ فِیْ الْمَعَاصِیْ وَزَنٰی وَفَسَقَ.وہ گناہوں کے ارتکاب میں لگ گیا حتیٰ کےکھلی کھلی بے حیائی کے کام کرنے شروع کر دئے.اور جب فَـجَرَالْحَالِفُ کہیں تو معنے ہوں گے کَذِبَ قسم کھانے والے نے جھوٹی قسم کھائی.نیز کہتے ہیں فَـجَرَفُلَانًا اور مراد یہ ہوتی ہے کہ کَذَّبَہٗ وَعَصَاہُ وَخَالَفَہٗ یعنی فلاں شخص کو جھٹلایا اور اس کی مخالفت کی اور اس کے خلاف کہا.اور جب فَـجَرَ اَمْرُ الْقَوْمِ کا فقرہ کہیں تو معنے ہوں گے فَسَدَ قوم کا معاملہ خراب ہو گیا.اور جب فَـجَرَ فُلَانٌ عَنِ الْحَقِّ کہیں تو معنے ہوں گے عَدَلَ عَنْہُ.حق بات سے پھر گیا (اقرب) پس اَلْفَجَرَۃُ کے معنے ہوں گے (۱)حق بات سے پھرنے والا (۲)جھوٹی قسمیں کھانے والے (۳)نافرمان اور خدا کے احکام کو جھٹلانے والے (۴)بے حیائی کے کام کرنے والے (۵)ایسے لوگ جن کا معاملہ خراب ہو چکا ہو.تفسیر.یہ سمجھ لو کہ یہ تباہ ہونے والے لوگ ہی کافر اور فاجر ہیں گویا واقعہ تمہیں خود بخود بتا دے گا کہ کون لوگ ایمان لانے والے ہیں اور کون لوگ کفر اور فسق و فجور میں ترقی کرنے والے ہیں.اب تم لوگوں کو دیکھ کر یہ نہیں
Page 282
کہہ سکتے کہ مکّہ میں سے کون سے لوگ ایمان لائیں گے اور کون سے لوگ انکار کریں گے مگر جس وقت اسلام کا باغ لگا آدمی اس طرف بھاگ پڑیں گے جس طرح انگور اور کھجور اور دانے اور زیتون اور میوے وغیرہ ہیں.اور جانور اُس طرف بھاگ پڑیں گے جس طرف کیکر کے درخت کھڑے ہیں.جو لوگ انگوراورکھجور وغیر ہ کی طرف جائیں تم سمجھ لو کہ وہ آدمی ہیں جو کیکر کے درختوں یا چارہ وغیر ہ پر مُنہ مارنے کے لئے دوڑ پڑیں اُن کے متعلق تم یہ یقین کر لو کہ وہ بھیڑیں اور بکریاں ہیں.ایک دن آئے گا جب ان کو ذبح کر دیا جائے گا.اور مسلمان اُن پر غلبہ حاصل کر لیں گے.خ خ خ خ
Page 283
سُوْرَۃُ التَّکْوِیْرِ مَکِّیَّةٌ سورۃ تکویر.یہ سورۃ مکّی ہے.وَ ھِیَ تِسْعٌ وَّ عِشْرُوْنَ اٰیَةً دُوْنَ الْبَسْمَلَةِ وَ فِیْھَا رُکُوْعٌ وَّاحِدٌ اور اس کی بسم اللہ کے علاوہ اُنتیس آیات ہیں اور ایک رکوع ہے.سورۃتکویر مکی ہے سورۃ التکویرمکّی ہے.۶ قبل ازہجرت یا اس سے کچھ پہلے کی معلوم ہوتی ہے.سورۃ تکویر میں قیامت کا ذکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سورۃ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ مَنْ سَرَّہٗ اَنْ یَّنْطُرَ اِلٰی یَوْمِ الْقِیَامَۃِ کَاَنَّہٗ رَأْیُ عَیْنٍ فَلْیَقْرَأْ اِذَالشَّمْسُ کُوِّرَتْ وَاِذَا السَّمَآءُ انْفَطَرَتْ وَاِذَالسَّمَآءُ انْشَقَّتْ اَخَرَجَہُ اَحْمَدُ وَ التِّرْمَذِیُّ وَحَسَّنَہٗ وَالْحَاکِمُ وَصَحَّحَہٗ (تفسیر روح المعانی سورۃ التکویر ابتدائیہ ) یعنی ابن عمرؓ رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو قیامت کو اس طرح معلوم کرنا چاہے جس طرح آنکھوں دیکھی چیز اُسے اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَاِذَا السَّمَآءُ انْفَطَرَتْ وَاِذَا السَّمَآءُ انْشَقَّتْ.سے شروع ہونے والی سورتیں پڑھنی چاہئیں.ترمذی نے اس روایت کو حسن اور حاکم نے صحیح کہا ہے اور مسند احمد بن حنبل میں بھی یہ روایت مذکور ہے.اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اس سورۃ میں ایک یوم القیامۃ کا جو نقشہ کھینچا گیاہے وہ ایسا تفصیلی ہے کہ یوم القیامۃ آنکھوں کے سامنے آجاتا ہے.باقی رہا یہ سوال کہ اس سے مراد وہ یوم القیامۃ ہے جو تمام بنی نوع انسان کے مرنے کے بعد آئے گا یا کوئی اور ہے.قیامت سے مراد بعثت انبیاء سو اس بارہ میں یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن کریم میں قیامت کا لفظ کئی معنوں میں استعمال ہے.مرنے کے بعد جب سب لوگ زندہ کئے جائیں گے اس کے لئے بھی قیامت کا لفظ استعمال ہوتا ہے.نبی کی بعثت کے لئے بھی قیامت کا لفظ استعمال ہوتا ہے.نبی کے دشمنوں کی تباہی کے لئے بھی قیامت کا لفظ استعمال ہوتا ہے.اور نبی پر ایمان لانے والوں کی ترقی کے لئے بھی قیامت کا لفظ استعمال ہوتا ہےنبی کی بعثت بھی قیامت ہے کیونکہ وہ موجب ہوتی ہے ہر ایک چیز کے اُبھر آنے کا.نبی جب ظاہر ہوتا ہے تو نیکی کی طاقتیں بھی اُبھر آتی ہیں اور بدی کی طاقتیں بھی اُبھر آتی ہیں اس لئے وہ بھی ایک قیامت ہوتا ہے کیونکہ اُس کے آنے پر دنیا میں ایک حشر برپا
Page 284
ہو جاتا ہے اور قلوب کی مخفی طاقتیں ظاہر ہو جاتی ہیں چنانچہ دیکھ لو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ابو بکر کے ابوبکرؓ بننے کا اور ابو جہل کے ابو جہل بننے کا موجب ہوئے ورنہ ابوجہل تو پہلے ابوالحکم کہلاتا تھا جب اُس کو وہ روحانی وجود نظر آیا جس کے ظاہر ہونے میں اُس نے اپنی طاغوتی طاقتوں کی موت دیکھی تو یکدم اس نے اپنی طاغوتی قوتوں کو بڑھا دیا تا کہ وہ اس نورانی وجود کو دنیا سے مٹا دے تب اس کی وہ شکل ظاہر ہوئی جس سے آج ہم سب نفرت کرتے ہیں اگر رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم نہ آئے ہوتے اور لوگ ابوالحکم سے ملتے تو شاید تاریخوں میں وہ یہ ذکر کرتے کہ ابوالحکم عرب کا ایک شریف اور بااخلاق رئیس تھا.لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غالب نورانی وجود کو دیکھ کر اس کی طاغوتی قوتیں جوش میں آگئیں اور اس کا اندرونی گند دنیا پر ظاہر ہو گیا.اسی طرح اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ آئے ہوتے اور لوگ حضرت ابوبکرؓ سے ملتے تو وہ تاریخوں میں ذکر کرتے کہ ابو بکر عرب کا ایک شریف، اچھا اور دیانتدار تاجر تھا.لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے نتیجہ میں ابو بکر کا حُسن اس رنگ میں ظاہر ہوا کہ آج تک سب دُنیا اُس کی تعریف پر مجبور ہے.پس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے ہی ابوبکر ابوبکرؓ بنا اور ابو جہل ابو جہل بنا.موجودہ زمانہ میں ہی دیکھ لو مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی اگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مخالفت نہ کرتے یا مولوی ثناء اللہ صاحب مخالفت نہ کرتے اور ہمیں اُن کا تاریخوں میں ذکر کرنا پڑتا تو ہم کہتے کہ یہ اپنی قوم کے بڑے عالم تھے.صداقت سے ان کی اندرونی دشمنی کبھی ظاہر نہ ہوتی مگر اب ان کی تحریروں کو پڑھ کر یوں پتہ لگتا ہے کہ سچ کو دیکھ کر اُن کا دل چاہتا ہے کہ اُسے بالکل ملیا میٹ کر دیں.یہ انقلاب صرف حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بعثت سے ہوا ورنہ اُن کی یہ طاقت اُبھرنی نہ تھی یا حضرت خلیفہ اول رضی اللہ عنہ کو اگر ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بغیر ملتے تو ہم یہی کہتے کہ آپ ایک بڑے عالم تھے.طبیب تھے اور غریب پروری کا مادہ اپنے اندر رکھنے والے تھے اس سے زیادہ ہمیں اُن کی نیکی نظر نہ آتی.الغرض نبی کی بعثت بھی ایک قیامت ہی ہے پھر وہ گھڑی بھی ایک قیامت ہوتی ہے جب نبی کی بعثت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے دشمنوں کو تباہ کرتاہے کیونکہ قیامت بمعنی موت بھی آتی ہے.خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَنْ مَّاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِیَامَتُہٗ (مجمع بحار الانوار زیر لفظ قیامۃ و تشیید المبانی حدیث نمبر ۲۷۶) جو مر جاتا ہے اس کی قیامت اُسی وقت آجاتی ہے.اگر ایک شخص کی موت کو قیامت کہہ سکتے ہیں.تو قوم کی موت اور تباہی قیامت کہلانے کی زیادہ مستحق ہے.قرآن اور حدیث میں لفظ قیا مت کے تین استعمال علّامہ شیخ محمد طاہر سندھی مصنّف مجمع بحار الانوار لفظ
Page 285
قیامت کے نیچے لکھتے ہیں وَقَدْ وَرَدَ فِیْ الْکِتٰبِ وَالسُّنَّۃِ عَلٰی ثَلَاثَۃِ اَقْسَامٍ اَلْقِیَامَۃُ الْکُبْرٰی وَالْبَعْثُ لِلْجَزَائِ وَالْوُسْطٰی وَھِیَ اِنْقِرَاضُ الْقَرْنِ وَالصُّغْریٰ وَھُوَ مَوْتُ الْاِنْسَانِ یعنی قرآن کریم اور حدیث سے قیامۃ کے تین استعمال ثابت ہیں.قیامت کبریٰ جو جزاء سزاء کے لئے بعثتِ ثانیہ کے مفہوم میں استعمال ہوتی ہے اور قیامت وسطٰی جس سے مراد پہلی صدی کا خاتمہ ہے یعنی جب مسلمانوں میں تنزّل کے آثار ظاہر ہوں گے اور صغریٰ یعنی موت انسانی.قرآن کریم سے اسی امر کی تصدیق ہوتی ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ روشنی لفظ قیامت اور ساعۃ پر پڑتی ہے (یہ دونوں لفظ ہم معنی استعمال ہوتے ہیں)چنانچہ قرآن کریم پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ لفظ قیامت (۱)نبی کی قوم کی ترقی (۲)دشمنوں کے تنزّل (۳)اور نبی کی قوم کے زمانۂ ترقی کے بعد تنرّل کے دَور پر بولا جاتا ہے.پہلے معنوں کے مطابق قرآن کریم میں سورۂ قمر کی یہ آیت ہے اِقْتَرَبَتِ السَّاعَۃُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ(القمر:۲) ساعت یعنی قیامت قریب ہی آگئی ہے اور چاند پھٹ گیا ہے عام طور پر مسلمانوں میں شق قمر کے معجزہ کی وجہ سے یہ خیال پیدا ہو گیا ہے کہ اس میں شق قمر کے معجزہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے حالانکہ اس آیت میں کوئی ایسی بات نہیں جس سے معلوم ہو کہ صرف اسی معجزہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کیونکہ اس آیت میں شق قمر کے مضمون کو ضمنی امر کے طور پر بیان کیا گیا ہے اور اقتراب ساعۃ کی دلیل قرار دیا گیا ہے.قرآن مجید میں قیامت سے مراد کفار کی تباہی پس شق قمر کے کوئی بھی معنے لو خواہ عرب کی حکومت کے زوال کے یا اس معجزہ کے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں اور کافروں کو اس طرح دکھایا کہ انہیں چاند پھٹتا ہوا نظر آیا بہرحال یہ امر ثابت ہے کہ قرآن کریم اس انشقاق قمر کو اس امر کی دلیل کے طور پر پیش کرتا ہے کہ اب قیامت کو آیا سمجھو.اور یہ ظاہر ہے کہ وہ قیامتِ کبریٰ جس وقت تمام عالم مر کر دوبارہ اُٹھے گا اب تک کہ اس نشان پر تقریباً تیرہ سو ستر سال گزر چکے ہیں ظاہر نہیں ہوئی اور جبکہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس امت میں مسیح اور مہدی ظاہر ہونے والے ہیں اور ان کے ذریعہ سے اسلام پھر ترقی کرنے والا ہے اگر ان کا زمانہ اور اُن کے بعد کا زمانہ عام مسلمان (کیونکہ ہمارے نزدیک وہ ظاہر ہو چکے ہیں) سات سو سال کا بھی تسلیم کر لیں تو قیامت دو ہزار سال بعد آئے گی ان حالات میں کفار کو اقتراب ساعۃ سے ڈرانے کے کوئی بھی تو معنے نہیں رہتے اور یہ ایک تمسخر ہو جاتا ہے جو قرآن کریم کی شان سے بعید ہے کہ وہ کفّار مکہ کو ڈراتا ہے کہ اے کفارِ مکّہ! تم تباہ ہو جائو گے اور اسلام غلبہ پا لے گا پھر وہ زوال پذیر ہو گا اور اس کے زوال پر صدیاں گزرنے پر ایک مسیح ظاہر ہو گا اور وہ دنیا پر غالب آکر
Page 286
اسلام کو غالب کرے گا اور پھر ایک لمبے عرصۂ ترقی کے بعد کفر ترقی کرے گا اور اس وقت دنیا تباہ ہو جائے گی اور ہم تم کو اے کفار جن کا نام و نشان مٹے ہوئے اس وقت تک دو ہزار سال ہو چکے ہوں گے اس دن سے ڈراتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ وہ اب سے صرف دو ہزار سال کے بعد آنے والا ہے کوئی عقلمند آدمی بھی لوگوں کے سامنے ایسی بات پیش کر سکتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف جو سب عالموں سے اعلم ہے وہ بات کیوں منسوب کی جاتی ہے جسے خود انسان اپنی نسبت منسوب کیا جانا پسند نہیں کرتا.پس صاف ظاہر ہے کہ اس اقتراب ساعۃ سے مراد اسلام کا غلبہ ہے اور جیسا کہ عرب کے محاورہ سے ظاہر ہے قمر کے معنے عرب کی حکومت یا عرب کے سردار کے ہوتے ہیں(شرح زرقانی علی موطا امام مالک کتاب الجنائز باب ما جاء فی دفن المیت ،السیرۃ النبویۃ لابن ہشام امر صفیۃ ام المومنین).پس اللہ تعالیٰ نے پہلے کفار اور مسلمانوں کو انشقاقِ قمر کا معجزہ دکھایا پھر قرآن کریم میں اس معجزہ کی تفسیر بیان فرما دی اور فرمایا کہ تم لوگ انشقاق قمر کا معجزہ دیکھ چکے ہو وہ اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ عربوں کی حکومت (یعنی کفار عربوں کی حکومت) اب تباہ ہونے والی ہے اور اسلام کی ترقی کا وقت جو دشمنانِ اسلام کے لئے ایک قیامت کا نظارہ پیش کرے گا نزدیک آگیا ہے اور اس آیت میں ساعت یا قیامت سے مراد اسلام کی ترقی کا دَور ہے نہ کچھ اَور.اسی طرح سورۂ ممتحنہ میں بعض مسلمانوں کا ذکر کر کے کہ وہ بعض دفعہ مسلمانوں کی خبریں کفار کو بھجوا دیتے ہیں اور یہ بُرا فعل ہے فرماتا ہے اِنْ يَّثْقَفُوْكُمْ يَكُوْنُوْا لَكُمْ اَعْدَآءً وَّ يَبْسُطُوْۤا اِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ وَ اَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوْٓءِ وَ وَدُّوْا لَوْ تَكْفُرُوْنَ.لَنْ تَنْفَعَكُمْ اَرْحَامُكُمْ وَ لَاۤ اَوْلَادُكُمْ١ۛۚ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ١ۛۚ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ١ؕ وَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ (الممتحنة:۳،۴ )یعنی یہ کفار تو تمہارے پکّے دشمن ہیں اگر تم کو پکڑنے کا موقعہ ملے کوئی موقعہ دشمنی کا جانے نہ دیں اور اپنے ہاتھ تمہاری طرف سزا کے لئے بڑھائیں اور اسی طرح زبان درازی سے نہ چوکیں اور ان کا تو دل یہی چاہتا ہے کہ تم کافر ہو جائو.لیکن یاد رکھو کہ خواہ یہ لوگ تمہارے عزیز ہوں یا اولاد یہ تم کو قیامت کے دن نفع نہ دیں گے اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان اس دن امتیاز قائم کر دے گا اور اللہ تعالیٰ اُسے جو تم کرتے ہو دیکھ رہا ہے.اس آیت میںیوم قیامت سے مراد وہی فیصلہ کا دن ہوا جو اس دنیا میں فتح مکہ اور بعد کے زمانہ میں ظاہر ہوا اور جس نے کافر و مومن کو الگ الگ کر دیا.قومی ترقی میں کفار کوئی مدد نہ کر سکے حتی کہ غزوہ حنین میں بجائے فائدہ پہنچانے کے کفار مسلمانوں کے بھاگنے کا موجب ہوئے اور جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت عباسؓ نے آواز دی کہ اے انصار! اے بیعتِ رضوان کرنے والو! خدا کا رسول تُم کو بلاتا ہے تو انصار غیر معمولی قربانی کر کے لوٹے اور مسلمانوں کی شکست فتح سے بدل گئی لیکن کفار نے جا کر مکہ ہی میں دم لیا(السیرة النبویة لابن ہشام زیر عنوان غزوة حنین فی ستة ثمان بعد الفتح).پس اس
Page 287
آیت کا مضمون جب پوری طرح اس دنیا میں پورا ہوا ہے بغیر کسی تاویل یا توجیہہ کے.تو اس کومرنے کے بعد کے زمانہ پر لگانا کوئی معنے نہیں رکھتا.اسی طرح سورۂ بقرہ میں فرماتا ہے زُيِّنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَ يَسْخَرُوْنَ مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا١ۘ وَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ١ؕ وَ اللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (البقرة:۲۱۳)اس آیت میں بھی یَوْمَ الْقِیَامۃ فتح مکّہ وغیرہ قسم کے واقعات کی نسبت استعمال ہوا ہے.یہاں فرمایا گیا ہے کہ کافر ورلی زندگی کو اچھا سمجھتے ہیں یعنی موجودہ وقت کی طاقت پر گھمنڈ رکھتے ہیں حالانکہ انجام مسلمانوں کا اچھا ہو گا اور قیامت کے دن مسلمان کافروں پر غالب ہوں گے اور انہیں بے حساب رزق ملے گا.یہ واقعہ اسی دنیا میں فتح مکّہ اور بعد کے واقعات سے پورا ہوا.اگر یہ معنے کرو کہ مسلمان مرنے کے بعد قیامت کے دن کافروں پر غالب ہوں گے تو اول تو یہ دلیل و برہان نہیں رہتی کیونکہ مرنے کے بعد کے واقعہ کو حجت کے طور پر پیش کرنا ایک بے فائدہ امر ہے اس سے کون شخص ایمان حاصل کرسکتا ہے؟ مرنے کے بعد تو ایمان کا نفع ختم ہو جاتا ہے.دوسرے اس صورت میں آیت قرآنی کا یہ مطلب ہو گا کہ مسلمانوں کو غلبہ اس دنیا میں نہ ملے گا مرنے کے بعد ملے گا اور یہ بات بالبداہت غلط ہے.مسلمانوں کو فتح مکّہ اور بعد کی جنگوں سے اسی دنیا میں غلبہ ملا.اگر کہا جائے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بغیر حساب رزق دینے کا ذکر کیا ہے اور یہ بعد ازموت زندگی میں ہی ممکن ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ بغیر حساب کے دو معنے ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ عمل کی نسبت زیادہ ملنا گویا عمل کے حساب سے جس قدر ملنا چاہیے تھا اس سے زیادہ مل گیا.دوسرے معنے اس کے یہ ہوتے ہیں کہ جس کو رزق ملے گا وہ اُسے نہایت اچھی طرح خرچ کرے گا اور اُسے اس کا حساب نہ دینا ہو گا.حساب اُسی وقت دیا جاتا ہے کہ جب فرض کو صحیح طور پر بجا نہ لایا جائے.چنانچہ احادیث میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے حساب لیا گیا تباہ ہوا.اس پر حضرت عائشہؓ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے فَسَوْفَ یُحَاسِبُ حِسَابًا یَّسِیْرًا.کہ مومنوں کا بھی حساب ہو گااس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حساب سے مراد یہ ہے کہ پوری طرح حساب لیا جائے ورنہ مومن کا حساب تو یوں ہی سرسری ہے اور نہ ہونے کے برابر ہے (بخاری کتاب الرقاق باب من نوقش الحساب عذّب) پس بغیر حساب کے ایک معنے یہ ہیں کہ مومنوں کو جو ملے گا وہ اُسے نیک طور پر خرچ کریں گے اور اس طرح حساب کی زحمت سے بچ جائیں گے اور یہ دونوں معنے مسلمانوں کی زندگی میں ہی پورے ہو گئے مرنے کے بعد کی قیامت کا انہیں انتظار نہیں کرنا پڑا.جو کچھ مسلمانوں کو ملا بِلا حساب ملا.اُن کی قربانیاں بے شک بہت تھیں مگر خدا تعالیٰ کی طرف سے جو اجر انہیں ملا وہ ان کی قربانیوں سے بہت زیادہ
Page 288
تھا.اونٹ اور بکریاں چرانے والے ساری دنیا کے بادشاہ ہو گئے اور مقہور اور مغلوب قوم زبردست بادشاہتوں کی مالک ہو گئی.اسی طرح دوسرے معنوں کے رُو سے بھی انہیں بغیر حساب ملا یعنی وہ ایسے تقویٰ کے مالک ہوئے کہ آج تک اُن کی نیکی کی دنیا تعریف کر رہی ہے.انہوں نے بہت کچھ کمایا لیکن گنْوایا نہیں.اُسے اس طرح خرچ کیا کہ اس دنیا میں نیکی اور اگلے جہان میں ثواب کاموجب ہوا (اس بارہ میں دیکھو سورۂ نور آیت ۳۸ وسورۂ ص آیت ۴۹ و سورۂ زمر آیت ۱۰ )خلاصہ یہ کہ آیت مذکورہ بالا میں جس یومِ قیامت کا ذکر ہے اس سے مراد غلبۂ اسلام ہے کیونکہ اسی موقعہ پر مسلمانوں کو کفار پر فوقیت حاصل ہو چکی تھی اور بغیر حساب رزق بھی مل گیا تھا.اسی طرح سورۃ قیامۃ میں دو قیامتوں کا ذکر ہے ایک اس دنیا کی اور ایک آخرۃ کی چنانچہ ایک قیامت کا یوں ذکر ہے فَاِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ (القیامة :۸ تا ۱۰) یعنی اس وقت چاند گرہن لگے گا اور اس کے بعد سورج گرہن لگے گا اور گرہن مرنے والی قیامت کی علامت نہیں بلکہ مہدی مسعود کی علامت احادیث سے ثابت ہے پس ان آیات میں جس قیامت کا ذکر کیا ہے وہ آخری زمانہ میں اسلام کے احیاء کی قیامت ہے نہ مرنے کے بعد اُٹھنے والی.اِن آیات کے سوا متعدد جگہ قرآن کریم میں قیامت اور ساعۃ سے مراد اس دنیا کے کسی عظیم الشان انقلاب کو مراد لیا گیا ہے اور آیات زیر تفسیر میں بھی جس قیامت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے (جیسا کہ اگلے مضامین سے ثابت ہو گا) اس سے مراد اس دنیا کی قیامت ہے جبکہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو مرنے کے بعد پھر زندہ کرے گا اور اسلام مٹ کر پھر تازہ ہو گا اور اس زمانہ کی علامات اس اور اس سے بعد کی سورۃ میں بیان کی گئی ہیں.احادیث میں قیامت سے مراد انقلاب دنیا جیسا کہ قرآن کریم کے محاورہ میں قیامت سے مراد اس دنیا کا انقلاب بھی لیا گیا ہے.احادیث نبی کریم ؐ میں بھی قیامت اور ساعۃ ان معنوں میں مستعمل ہوئے ہیں چنانچہ بخاری کتاب الایمان باب سوال جبریل عن علم الساعۃ میں ہے کہ ایک دفعہ حضرت جبریل انسانی شکل میں متمثل ہو کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ کے صحابہ کو بھی نظر آئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ مَتَی السَّاعَۃُ قیامت کب آنے والی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مَا الْمَسْئُوْلُ عَنْھااَعْلَمُ مِنَ السَّائِلِ وَ سَاُخْبِرُکَ عَنْ اَشْرَاطِھَا اِذا وَلَدَتِ الْاَمَۃُ رَبَّھَا وَاِذَا تَطَاوَ لَ رُعَاۃُ الْاِبِلِ الْبُھْمِ فِیْ الْبُنْیَانِ یعنی اس بارہ میں سائل سے زیادہ مجھے علم نہیں ہاں میں اُس کی علامات بتا دیتا ہوں.اس کی علامات یہ ہیں کہ لونڈی اپنے مالک کو جنے گی اور اونٹوں کے چرانے والے اونچے اونچے مکان بنائیں گے چنانچہ یہ بنو عباس کی ترقی کے زمانہ میں ہوا.اکثر بادشاہوں نے لونڈیوں کو گھر میں ڈالا اور ان کی اولاد بادشاہ ہوئی اور ان کے رشتہ داروں کے ذریعہ سے
Page 289
عرب حکومت تبا ہ ہو گئی.اسی طرح اس زمانہ میں بجائے محنت اور قربانی اور سفروں کے عرب لوگوں نے شہری زندگی اختیا کر لی اور بڑی بڑی عمارتیں بنانے میںمشغول ہو گئے.ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک مجلس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم باتیں کر رہے تھے کہ ایک شخص آیا اور اس نے ساعت کے بارہ میں سوال کیا آپ بات کرتے رہے اور اُس کی بات کا جواب نہ دیا جب پہلی بات ختم کر چکے تو فرمایا ساعت کے بارہ میں سوال کرنے والا کہاں ہے.سوال کرنے والے نے کہا کہ میں حاضر ہوں اس پر آپ نے فرمایا فَاِذَا ضُیِّعَتِ الْاَمَانَۃُ فَانْتَظِرِ السَّاعَۃَ یعنی جب امانت میں کمی آجائے گی اُس وقت سے قیامت کا انتظار کرو.اِس پر اُس شخص نے کہا فَکَیفَ اِضَاعَتُھَا؟ یا رسول اللہ امانت کس طرح ضائع ہو گی اس پر آپ نے فرمایا اِذَا وُسِّدَ الْاَمْرُ اِلٰی غَیْرِ اَھْلِہٖ فَانْتَظِرِ السَّاعَۃَ (بخاری کتاب العلم باب من سُئل علمًا وھو مشغولٌ فی حدیثہٖ) یعنی امانت سے مراد امانتِ حکومت ہے پس جب حکومت نااہل لوگوں کے سپرد کی جائے گی اس وقت سے قیامت کے منتظر ہو جائو.اس جگہ قیامت سے مراد مسلمانوں کی تباہی اور تنزّل کا وقت ہے.اسی طرح بخاری میں آتا ہے اِنَّ مِنْ اَشْرَاطِ السَّاعَۃِ اَنْ یَّرْفَعَ الْعِلْمُ وَیَثْبُتُ الْجَھْلُ وَیُشْرَبُ الْخَمْرُ وَیَظْھَرُ الزِّنَا (بخاری کتاب العلم باب رفع العلم و ظھور الجھل ) یعنی قیامت کی علامات میں سے یہ علامات ہیں کہ علم اُٹھ جائے گا اور جہالت قائم ہو جائے گی اور شراب پی جائے گی اور زنا علی الاعلان کیا جائے گا یعنی کنچنیوں کا طریق رائج ہو جائے گا اور لوگ اپنی زنا کاریوں کا مجالس میں فخر سے ذکر کریں گے.اِ س حدیث میں قیامت سے مراد اسلام کا تنزّل ہے.اسی طرح بخاری کی حدیث ہے لَا تَقُوْمُ السَّاعَۃُ حَتّٰی یُقْبَضُ الْعِلْمُ وَتَکْثَرُ الزَّلَازِلُ وَیَتَقَارَبُ الزَّمَانُ وَتَظْھَرُ الْفِتَنُ وَیَکْثُرُ الْھَرَجُ وَھُوَالْقَتْلُ وَحَتّٰی یَکْثُرُ فِیْکُمُ الْمَالُ فَیَفِیْضُ (بخاری کتاب الاستسقاء باب ماقیلَ فی الزلازل و الآیات) یعنی قیامت اُس وقت تک نہ آئے گی جب تک علم مٹ نہ جائے اور زلازل کثر ت سے نہ آئیں اور علمِ تاریخ ترقی نہ کر جائے اور کثرت سے فتن ظاہر نہ ہوں اور قتل کا رواج ترقی نہ کر جائے اور مال کی اس قدر زیادتی نہ ہو جائے کہ لوگ مسرف ہو جائیں.یہ حدیث بھی مسلمانوں کے تنزّل کو قیامت کا نام دیتی ہے.اسی طرح بخاری میں حدیث ہے لَاتَقُوْمُ السَّاعَۃُ حَتّٰی تُقَاتِلُوْا قَوْمًا نِعَالُھُمُ الشَّعْرُ.وَلَا تَقُوْمُ السَّاعَۃُ حَتّٰی تُقَاتِلُوْا قَوْمًا کَاَنَّ وُجُوْھُھُمُ الْمَجَانُ الْمُطْرِقَۃُ (بخاری کتاب الجہاد باب قتال الذین ینتعلون
Page 290
الشعر) یعنی قیامت اس وقت تک نہ آئے گی جب تک کہ تم اس قوم سے جنگ نہ کرو کہ ان کی جوتیاں بالوں والی ہوں گی.اور ان کے منہ ڈھالوں کی طرح چپٹے ہوں گے یہ ترکوں کے حملوں کی طرف اشارہ ہے اور مراد یہ ہے کہ اسلامی تنزّل کا زمانہ ترکوں کے حملوں سے شروع ہو گا.اسی طرح حدیث میں ہے کہ بُعِثْتُ اَنَا وَالسَّاعَۃُ کَھَاتَیْنَ یَعْنِی اِصْبَعَیْنِ (بخاری کتاب الرقاق باب قول النبی بعثت اَنَا وَالسَّاعَۃُ کَھَاتَیْنِ) یعنی آپ نے اپنی دو انگلیوں کو جوڑ کر دکھایا اور فرمایا میرا اور قیامت کا زمانہ اسی طرح ساتھ ملا ہوا ہے.یہ امر ظاہر ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ پر تو تیرہ سو سال ہو گئے اور اب تک قیامت نہیں آئی.پس اس جگہ قیامت کے معنے کچھ اور ہیں اور وہ معنے اسلام کی ترقی کے ہیں اور آپ کا ارشاد یہ ہے کہ بعض نبی ایسے آئے ہیں کہ اُن کی قوم نے اُن کے مرنے کے بہت بعد جا کر ترقی کی ہے مگر مجھ سے اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ میرے زمانہ میں ہی اسلام کی ترقی ہو جائے گی چنانچہ ایسا ہی ہوا.اسی طرح ترمذی میں ہے اِقْتِرَابُ السَّاعَۃِ ھَلَاکُ الْعَرَبِ (جامع الترمذی کتاب المناقب باب فضل العرب) یعنی قیامت کے قریب آنے کے ایک معنے عربوں کی ہلاکت کے ہیں چنانچہ اِقْتَرَبَتِ السَّاعَۃُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ کے میں نے یہی معنے کئے ہیں.خلاصہ یہ کہ قرآن کریم اور احادیث میں لفظِ قیامت کے معنے قیامتِ کُبریٰ کے بھی ہیں یعنی اس قیامت کے جو تمام انسانوں کی ہلاکت سے یا اُن کے دوبارہ اُٹھنے سے ظاہر ہو گی اور اس کے معنے کسی قومی ترقی کے بھی ہیں اور کسی قوم کے تنزّل کے بھی اور کسی فرد کی موت کے بھی.پس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ جو شخص یوم القیامۃ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہے وہ ان سورتوں کو پڑھ لے اس سے یہ نتیجہ نکالنا درست نہیں ہو سکتا کہ ان سورتوں میں صرف اسی قیامت کا ذکر ہے جو مرنے کے بعد آنے والی ہے اگر قرآن قیامت کے کئی معنے لے سکتا ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس لفظ کو اس کے متعدد معانی میں استعمال فرما سکتے ہیں بہرحال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے کہ جس قیامت کا اِن سورتوں میں ذکر آتا ہے اس قیامت کا ایک تفصیلی نقشہ ان میں کھینچ دیا گیا ہے.ایسا تفصیلی کہ اس کو دیکھنے کے بعد یوں معلوم ہوتا ہے گویا یوم القیامۃ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے چنانچہ بعد میں اس سورۃ کی جو تفصیل کی جائے گی اس سے معلوم ہو گا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا وہ بالکل درست ہے.سورۂ تکویر کا سورۂ عبس اور پہلی سورتوں سے تعلق اس سورۃ کا تعلق پہلی سورۃ بلکہ پہلی سورتوں سے یہ ہے
Page 291
کہ ان سورتوں میں غلبۂ اسلام اور قیامتِ کُبریٰ کا ذکر تھا اور اسلام کا غلبہ کم سے کم دو دفعہ مقدر تھا جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت دو دفعہ مقدر تھی پس وہ قیامت جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ قائم ہوئی تھی اس کے دو بڑے مظہر تھے جیسا کہ قرآن کریم سے ثابت ہے اور سورۂ جمعہ میں اس کا ذکر آتا ہے پس ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں یہ قیامت آئی تھی اور ایک دفعہ تیرہ سو سال کے بعد یعنی آپ کے دَورِ اوّل پر ایک ہزار سال تنزّل کا زمانہ گزر جانے کے بعد آنی مقدّر تھی.مصلح موعود کی پیشگوئی قرآنی آیت کی مصدق قرآن کریم کے دوسرے مقامات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلام پر تنزّل کا بھی ایک دَور آنے والا تھا جیسا کہ يُدَبِّرُ الْاَمْرَ مِنَ السَّمَآءِ اِلَى الْاَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ اِلَيْهِ فِيْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗۤ اَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ(السجدة:۶) سے ظاہر ہوتا ہے.اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ امر اسلام کو آسمان سے زمین پر نازل فرمائے گا پھر ایک ہزار سال کے عرصہ میں وہ واپس اللہ تعالیٰ کی طرف چلا جائے گا چونکہ احادیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ترقی کا زمانہ تین قرن کا ہے (بخاری کتاب الرقاق باب ما یحذر من زھرة الدنیا)اس لئے ہزار سال تنزّل کے مل کر تنزّل کا زمانہ ۱۳۰۰ہجری پر ختم ہوتا ہے یا اندازًا ۱۸۸۶ء کو.٭ پس جب پہلے یہ بات بتائی کہ اسلام کا غلبہ ہو گا اور پھر اس پر ایک تنزّل کا زمانہ آئے گا تو ضروری تھا کہ یہ بھی بتایا جاتا کہ اس تنزل کے بعد کیا ہو گا تا کہ مسلمان دلبرداشتہ نہ ہو جا ئیں اور ہمت ہار کر نہ بیٹھ جائیں.حدیثوں میں آتا ہے ابویا سر بن اخطب جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کا ایک مشہور یہودی عالم تھا ایک دن کچھ اور یہود سمیت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا جب کہ آپ سورۂ بقرہ کی ابتدائی آیات الٓمّٓ.ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ١ۛۖۚ فِيْهِ پڑھ رہے تھے وہ یہ سُن کر اپنے بھائی حُیّی بن اخطب کے پاس گیا اور اُسے کہا کہ میں نے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم ) کو الٓمّٓ.ذٰلِكَ الْكِتٰبُ پڑھتے سُنا ہے.وہ کہنے لگا کیا تم سچ کہتے ہو؟ اُس نے کہا ہاں.اس ٭ حاشیہ: ۱۸۸۶ ء اس طور پر بنتا ہے کہ ۱۳۰۰ ہجری سالوں کو شمسی سالوں میں تبدیل کیا جائے.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ۶۳۲ء میں ہوئی اور ۱۳۰۰ ہجری سالوں کے شمسی سال ۱۲۶۲ بنتے ہیں.جب ان دونوں کو ملایا جائے تو ۱۸۸۶ ہوتے ہیں یا کسروں کو نکال دیا جائے تو ۱۸۸۵ اور ۱۸۸۶ء ہی وہ سال تھا کہ جب بانی سلسلہ احمدیہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسلام کی فتح کا علم دیا گیا اور آپ کے ذریعے سے ایک سلسلہ کی جو اسالم کی بنیاد کو مضبوط کرنے والا ہوگا خبر دی گئی اور یہ اطلاع دی گئی ہ آپ کی نسل سے ایک ایسا لڑکا بھی پیدا ہوگا جس کے ذریعے سے اسلام کی شہرت دنیا کے کناروں تک پہنچے گی اور وہ لڑکا اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق یہ راقم السطور ہی ہے جس کی خبر ۱۸۸۶ء کے شروع ہی میں دی گئی جو قرآنی پیشگوئی کی مصدق اور اس کو پورا کرنے والی ہے.وَاللہُ غَنِیٌّ لَا یُسْئَلُ عَنْہُ وَ ھُمْ یُسْئَلُوْنَ.
Page 292
پر حُیّیِ کچھ اور لوگوں کو ساتھ لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کےپاس پہنچا اور کہا کہ کیا درست ہے کہ آپ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسا کلام نازل ہوا ہے جس میں الٓمّٓ.ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ١ۛۖۚ فِيْهِ آتا ہے؟ آپ نے فرمایا.ہاں.وہ کہنے لگا تو پھر ڈر کی کوئی بات نہیں اگر آپ کا غلبہ بھی ہوا تو کل اکتّرسال رہے گا کیونکہ علم ابجد کے لحاظ سے الفؔ کا ایک لامؔ کے تیس اور میم کے چالیس عدد ہیں کل ۷۱ سال ہوئے.یہ ۷۱ سال ہم کسی نہ کسی طرح کاٹ لیں گے اس کے بعد آپ کا غلبہ نہیں رہ سکتا.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اَلٓمّٓصٓ بھی الہام ہوا ہے وہ کہنے لگا تو خیر ابجد کے لحاظ سے الفؔ کا ایک لامؔ کے تیس میمؔ کے چالیس اور صؔ کے نوّے کل ایک سو اکاسٹھ سال ہوئے یہ مدت پہلے سے زیادہ ہے مگر خیر کوئی زیادہ لمبا عرصہ نہیں.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اَلٓرٰ بھی الہام ہوا ہے کہنے لگا تو پھر دو سَو اکتیس سال بن گئے کیونکہ الفؔ کا ایک لامؔ کے تیس اور راءؔ کے دو سو.آپ نے فرمایا اَور سُن لو مجھ پر اَلٓمّٓرٰ بھی الہام ہوا ہے.تب اس نے کہا کہ یہ تو پہلے سے بھی گراں اور لمبا عرصہ ہے.الفؔ کا ایک لامؔ کے تیس میمؔ کے چالیسؔ اور راءؔ کے دو سَو ہوتے ہیں کل دو سَو اکہتر سال کا عرصہ ہوا.پھر اپنے ساتھیوں کو کہنے لگا یہاں سے چلو یہ معاملہ مشتبہ ہو گیا ہے.(فتح البیان زیر آیت الم ذالک الکتاب ) آنحضرت صلعم کی زبان سے اسلام کے تنزل کے بعد اس کے عروج کی پیشگوئی تو تنزّل کی پیشگوئیوں کو سُن کر دشمن بعض دفعہ یہ خیال کر لیتا ہے کہ اگر اس مذہب پر تنزّل ایک دن آنے ہی والا ہے تو کسی طرح درمیانی زمانہ کو ہم برداشت کر لیں گے آخر وقت آئے گا کہ یہ زمانہ گزر جائے گا اور پھر ہمارے غلبہ کے ایام آجائیں گے.اسی لئے نبی کبھی تباہی کی خبر پر اپنے زمانہ کو ختم نہیںکرتا بلکہ وہ ساتھ ہی یہ خبر بھی دیتا ہے کہ میرے بعد ایک اور نبی آنے والا ہے جو تنزّل کے بعد پھر ترقی اور ـغلبہ کا دروازہ قوم کے لئے کھول دے گا یوں تو ہمیشہ سے یہ قانون چلا آیا ہے کہ ترقی کے ساتھ ہی تنزل کا دور بھی وابستہ ہوتاہے لیکن نبی کبھی تنزل کے زمانہ کی خبر دینے پر اکتفا نہیں کرتا بلکہ وہ اس کے ساتھ ہی ایک نئے دَور کی بھی بشارت دیتا ہے اور اس طرح بتاتا ہے کہ گو میں مر جائوں گا مگر یہ سلسلہ کبھی مٹ نہیں سکتا.اگر درمیان میں عارضی طور پر کوئی تنزل کا زمانہ بھی آیا تو پھر کفر پر دین کے غلبہ کے ایام آجائیں گے.اس طرح کفر کو اپنی ترقی سے ہمیشہ مایوس رکھا جاتا ہے اور مومنوں کے دلوں کو تسلی دی جاتی ہے کہ وہ مایوس مت ہوں بلکہ اپنی ہمت کو مضبوط رکھیں.اپنے ارادوں کو بلند کریں اور اپنی نگاہ کو اونچا رکھیںکہ اسلام پھر غالب آئے گا اور کفر پھر تباہی و بربادی کے گڑھے میں گر ے گا.یہی فرق خدائی کلام اور ایک غیر کے کلام میں ہوتا ہے.بھلا کوئی غیر یہ طاقت رکھ سکتا ہے کہ وہ غیر متناہی ترقیات کی خبر دے سکے.خدا ہی ہے جو غیب کا علم رکھتا ہے اور پھر ساتھ ہی
Page 293
اپنے منشاء کو پورا کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہےاور اپنے پیاروں کو اس سے اطلاع دیتا رہتا ہے تاکہ وہ اور لوگوں تک ان باتوںکو پہنچا دیں اور اس طرح پیشگوئیاں اُن کے دلوں کی ڈھارس کا موجب بن جائیں.یوں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی تنزّل کا دَور آیا.حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی تنزل کا دَور آیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی تنزل کا دَور آیا مگر اس تنزل کا انبیاء کی پیشگوئیوں میں ضرور ذکر ہوتا ہے تاکہ جب یہ زمانہ آئے تو اُس وقت یہ تنزل بھی نبی کی صداقت کا ثبوت بن جائے اگر تنزل بغیر کسی پیشگوئی کے آجائے تو لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک اتفاقی بات ہے لیکن اگر تنزل آنے کی پہلے سے خبر موجود ہو تو مومن کہہ سکتے ہیں کہ یہ تنزل بھی ہماری صداقت کا ثبوت ہے کیوں کہ اس تنزل کی پہلے سے پیشگوئیاں موجود ہیں.لیکن اگر تنزل کی ہی خبر ہو تنزل کے بعد ترقی کی خبر نہ ہو تو یہ بھی دلوں کو مایوس کرنے والی بات ہو سکتی ہے اسی لئے جہاں ایک طرف تنزل کی خبر دی جاتی ہے تاکہ جب یہ دَور آئے تو خود تنزل اپنی ذات میں انبیاء کی صداقت کا ایک ثبوت ہو وہاں تنزل کے بعد ایک ترقی کی بھی خبر دی جاتی ہے تا کہ مسلمانوں کو اطمینان رہے اور کفر اپنی دائمی سربلندی کی کبھی امید نہ رکھے.اگر یہ ترقی کسی نبی سے وابستہ ہو تو اس نبی کی خبر دی جاتی ہے اور اگر کسی اور شخص سے وابستہ ہو تو اس کی خبر دی جاتی ہے.بہرحال یہ ایک عظیم الشان گُر ہے جو دلوں کو بڑھانے اور ان کو ڈھارس دینے کے لئے اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا ہے میرا اس کے متعلق ذاتی طور پر ایک بڑا زبردست تجربہ ہے میں نے اپنی کتاب ’’دعوۃ الامیر‘‘ میں اس نکتہ کو بیان کیا ہے کہ اسلام پر آج جو مصیبت آئی ہوئی ہے اس کی خبر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں تفصیلاً موجود ہے اور جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج سے ساڑھے تیرہ سو سال پہلے اس تنزل کی خبر دے چکے ہیں.بلکہ اس تنزّل کے بعد ایک ترقی کے دَور کی بشارت بھی آپ سُنا چکے ہیں تو مسلمانوں کے لئے مایوسی کی کوئی وجہ نہیں.یہ تنزل جتنا بڑھتا چلا جائے ہم کہیں گے کہ اس سے اسلام کی تکذیب ہونے کی بجائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت ثابت ہو رہی ہے کیونکہ آپ کے کلام میں ان کا پہلے سے ذکر موجود ہے.قرآن کریم میں اس کی مثال بھی پائی جاتی ہے چنانچہ سورۂ احزاب میں ذکر آتا ہے کہ جب کفار کے لشکر مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لئے جمع ہو گئے اور منافقوں نے طعنے دینے شروع کر دئے کہ دنیا کی فتوحات کے وعدے کہاں گئے تو اس وقت مومنوں کے ایمان اور بڑھ گئے اور انہوں نے کہا هٰذَا مَا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَ رَسُوْلُهٗ وَ صَدَقَ اللّٰهُ وَ رَسُوْلُهٗ١ٞ وَ مَا زَادَهُمْ اِلَّاۤ اِيْمَانًا وَّ تَسْلِيْمًا (الاحزاب :۲۳)یعنی اس کی خبر تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے دے چکے تھے اس لئے ہمارے لئے خوشی کا مقام ہے کہ خدا کے منہ کی بات پوری ہوئی.غم اور فکر کی کون سی بات ہے.تو دیکھو اس وعدہ کی وجہ سے وہ ڈرے نہیں
Page 294
لیکن اگر یہ وعدہ نہ ہوتا تو بہت ممکن تھا کہ وہ گھبرا جاتے.پس وہی چیز جس کو دشمن ڈرانے کے لئے استعمال کرتا ہے اسی میںایمان کی مضبوطی کا سامان اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوتا ہے.اور وہ سمجھتا ہے کہ جب خدا نے اس تنزل کی خبر دی تھی اور خدا تعالیٰ کے کلام میں یہ بات موجود تھی تو پھر میرے لئے اس میں گھبرانے کی کون سی بات ہے.غرض مومن کے لئے اُن ابتلائوں میں جو خدائی پیشگوئی کے ماتحت آئیں بڑی بھاری طاقت ہوتی ہے کیونکہ ان ابتلائوں اور ان مصیبتوں اور اُن دکھوں سے اللہ تعالیٰ کی باتیں پوری ہوتی ہیں.اگر وہ ابتلا نہ آئیں تو وہی دشمن جو ان ابتلائوں کو اسلام کے جھوٹا ہونے کی دلیل قرار دیتا ہے جھٹ یہ کہنے لگ جائے کہ تمہارے نبی نے تو یہ یہ خبر دی تھی مگر اب تک پوری نہیں ہوئی.لیکن جب وہ خبر پوری ہو جاتی ہے.جب پیشگوئیوں کے مطابق ایک تنزل کا دور آجاتا ہے تو اسی کو مذہب کے جھوٹا ہونے کا ثبوت قرار دے دیتا ہے حالانکہ یہ صداقت کا ثبوت ہوتا ہے.یہ اس نبی کی راستبازی کا ثبوت ہوتا ہے یہ کفر کی شکست کا ثبوت ہوتا ہےکیونکہ جیسے ترقی کے متعلق خدا تعالیٰ کی بات پوری ہوئی تنزل کے بارہ میں بھی خدا تعالیٰ کی بات پوری ہوئی اور یہی ثابت کرنا مذہب کا اولین کام ہوتا ہے.پس یہ ایک بڑا بھاری نکتہ ہے جس کو سمجھ لینے کے بعد زمانۂ تنزل میںبھی انسان کا ایمان کبھی متزلزل نہیں ہو سکتا بلکہ اس کا قدم ایک مضبوط چٹان پر قائم رہتا ہے وہ جانتا ہے کہ میرا مذہب بہرحال سچا ہے غلبہ کے ایام میں بھی وہ سچا تھا اور تنزل کے ایام میں بھی وہ سچا ہے کیونکہ اس تنزل کی وہ پہلے سے خبر دے چکا تھا.مگر افسوس کے مسلمانوں نے اس نکتہ کو نہ سمجھا اور وہ مایوسی کا شکار ہو گئے.میں نے اپنی کتاب دعوۃ الامیر میں اس بات کو ایک حد تک تشریح سے بیان کیا ہے اور اس امر پر روشنی ڈالی ہے کہ اسلام کے تنزل کی خبریں بھی اپنے اندر اسلام اور قرآن کی صداقت کا ثبوت رکھتی ہیں کیونکہ ان خبروں کا قرآن اور احادیث میں تفصیل سے ذکر آتا ہے اور پھر اس کے ساتھ ہی اسلام صرف تنزل کی خبر پر اکتفا نہیں کرتا بلکہ اس نے یہ خبر بھی دی ہوئی ہے کہ اس زمانہ میں تنزل کے بعد اسلام پھر اپنے کمال کو پہنچے گا.پھر کُفر اپنے مُنہ کے بل گرے گا اور پھر ساری دنیا پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کا غلبہ ہو گا.پس یہ تنزل اپنے اندر ایک ترقی کی بشارت رکھتا ہے.اور یہ تاریکی ایک سورج کے نمودار ہونے کی خبر دے رہی ہے اور جب حالت یہ ہے تو مسلمان کیوں مایوس ہیں اور کیوں وہ خدائی وعدوں کے مطابق غور نہیں کرتے کہ وہ آسمانی روشنی کہاں ظاہر ہوئی اور اس ظلمت کے پردے چاک کرنے والا سورج کس جگہ طلوع ہوا ہے.اسی سلسلہ میں مَیں نے اوپر ذکر کیا ہے کہ اس بار ہ میں مجھے ایک عجیب تجربہ ہوا ہے.سرحد کے ایک رئیس چوہدری فقیر محمد صاحب اگزکٹو انجینئر تھے وہ ایک دفعہ دہلی میںمجھے ملے اور انہوں نے مجھ سے ذکر کیا کہ ہم چار بھائی
Page 295
ہیں جن میں سے دو بھائی غیر احمدی ہیں اور دو بھائی احمدی ہیں.اپنے متعلق انہوں نے کہا کہ میں ابھی تک آپ کی جماعت میں شامل نہیں ہوا.مَیں نے اُن سے کہا کہ آپ کیوں احمدی نہیں ہوئے کیا آپ کو احمدیت کی صداقت کے متعلق کوئی شبہ ہے؟ ان کی طبیعت میں مذاق تھا وہ میرے اس سوال کے جواب میں کہنے لگے کہ مجھے تو ابھی تک احمدیت پر غور کرنے کا موقع نہیں ملالیکن بات یہ ہے کہ ہم پورا پورا انصاف کرنے کے عادی ہیں.روپیہ میں سے اٹھنّی ہم نے آپ کو دے دی ہے اور اٹھنّی دوسرے مسلمانوں کو دے دی ہے.میں نے بھی اُن سے مذاقًا کہا کہ خاں صاحب ہم تو اٹھنّی پر راضی نہیں ہوتے ہم تو پورا روپیہ لے کر چھوڑا کرتے ہیں.وہ کہنے لگے تو پھر اپنی توجہ سے لے لیجئے.میں نے کہا ہماری کوشش تو یہی ہے اللہ تعالیٰ جب چاہے گابقیہ اٹھنی بھی مل جائے گی.وہ اُس وقت مع اہل وعیال انگلستان کی سیر کو جا رہے تھے میری اس بات کو سُن کر انہوں نے کہا کہ خان محمد اکرم خان صاحب چار سدّہ والے میرے بھائی ہیں انہوں نے آپ کی بعض کتابیں میرے ٹرنک میں رکھ دی ہیں.میں نے اُن سے کہا بھی ہے کہ میں تو وہاں سیر کے لئے جا رہا ہوں ان کتابوں کے پڑھنے کا کہاں موقع ہو گا مگر وہ مانے نہیں اور زبردستی میرے ٹرنک میں انہوں نے کتابیں رکھ دی ہیں مگر اب تک مجھے پڑھنے کا موقع نہیں ملا.چنانچہ اس کے بعد وہ ولایت چلے گئے.ابھی تین مہینے ہی گزرے تھے کہ مجھے ایک چٹھی پہنچی.اس کے شروع میں ہی یہ لکھا تھا کہ میں اصل مطلب لکھنے سے پہلے آپ کی شناخت کے لئے یہ لکھنا چاہتا ہوں کہ میں وہ ہوں جو آج سے تین ماہ پہلے دہلی کے شاہی قلعہ میں آپ سے ملا تھا اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم نے پورا پورا انصاف کیا ہے اٹھنّی آپ کو دے دی ہے اور اٹھنّی غیر احمدیوں کو دے دی ہے جس پر آ پ نے کہا تھا کہ ہم تو پورا روپیہ لے کر چھوڑا کرتے ہیں سو آپ کے حکم کے مطابق اب ایک اور چونّی آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اور اپنے آپ کو بیعت میں شامل کرتا ہوں.اس کے بعد انہوں نے اسی مضمون کی طرف جس کا میں ابھی ذکر کر چکا ہوں اشارہ کیا اور لکھا کہ جب میں ولایت میں آیا اور میں نے مختلف مقامات کی سیر کی تو گو میں پٹھان ہوں اور مذہبی جوش میرے دل میں موجود ہے مگر کفر کی بڑھتی ہوئی طاقت کو دیکھ کر میرا دل پژمردہ ہوتا چلا گیااور میں نے کہا کہ اسلام اس قدر گر چکا ہے اور کفر اس قدر ترقی کر چکا ہے کہ اب بظاہر اسلام کے پنپنے اور کفر کے سرنگوں ہونے کا دنیا میں کوئی امکان نہیں.اسلام مر چکا ہے اب اُ س کے زندہ ہونے کی امید ایک واہمہ سے بڑھ کر حقیقت نہیں رکھتی.یہ خیالات تھے جو میرے دل پر غالب آتے چلے گئے اور اس قدر میرے دل میں مایوسی پیدا ہوئی کہ مجھے یقین ہو گیا کہ اب اسلام دنیا پر غالب نہیں آسکتا.ایک دن میرے دل پر اس خیال کا بے انتہاء اثر ہوا اور حالت مایوسی میں مَیں نے کہا آئو ان کتب کو پڑھ کر دیکھو جو میرے بھائی نے میرے ٹرنک میں رکھ دی تھیں چنانچہ پہلے ’’اسلامی اصول کی فلاسفی‘‘ نِکلی اور اُسے میں نے پڑھا اس کے بعد آپ کی کتاب
Page 296
’’دعوۃ الامیر‘‘ نکلی اوراسے میں نے پڑھنا شروع کیا.پڑھتے پڑھتے اس کتاب میں وہی ذکر آگیا جس نے میرے دل میں انتہائی طور پر مایوسی پیدا کر دی تھی یعنی اسلام کے تنزّل اور اس کے ادبار کا اس میں ذکر تھا مگر ساتھ ہی بتایا گیا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے تنزّل کے متعلق یہ پیشگوئی کی تھی جو پوری ہو گئی.وہ پیشگوئی کی تھی.جو پوری ہو گئی.غرض یکے بعد دیگرے اسلامی تنزّل کے متعلق کئی پیشگوئیاں تھیں جو پڑھنے میں آئیں اور جو واقعہ میں پوری ہو چکی تھیں.اس کے بعد آپ نے اسلام کی ترقی کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کا ذکر کیا ہے اور لکھا ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشگوئیاں پوری ہو گئیں جو اسلام کے تنزل کے ساتھ تعلق رکھتی تھیں تو وہ پیشگوئیاں کیوں پوری نہیں ہوں گی جو اسلام کے دوبارہ غلبہ کے متعلق ہیں.میں نے جب یہ مضمون پڑھا تو میرا دل خوشی سے بھر گیا مایوسی میرے دل سے جاتی رہی.امید جگمگا اٹھی اور میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں اُس وقت تک سونے کے لئے اپنے بستر پر نہیں جائوں گا جب تک آپ کو اپنی بیعت کا خط نہ لکھ لوںچنانچہ سونے سے پہلے میں یہ خط آپ کو لکھ رہا ہوں میری بیعت کو قبول کیا جائے.غرض سچی بات یہی ہے کہ جب وہ تکلیفیں اور وُہ دُکھ جو اسلام اور مسلمانوں پر آئے اُن کے متعلق یہ معلوم ہو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام تکالیف کی خبر پہلے سے دے چکے ہیں تو ان تکالیف میں بھی راحت محسوس ہونے لگتی ہے.اور انسان سمجھتا ہے کہ جیسے تنزل کی خبریں پوری ہو گئیں اسی طرح ایک دن اسلام کے غلبہ کی پیشگوئیاں بھی پوری ہو جائیں گی اسی طرح اگلی قیامت کا بھی ان پیشگوئیوں کے پورا ہونے سے ثبوت مل جاتا ہے کیونکہ جو خدا اس جہان میں مردہ روحوں کا احیاء کر سکتا ہے وہ اگلے جہان میں کیوں نہیں کر سکتا.اگر اس دنیا کی روحانی موت اور اس کا احیاء پیشگوئیوں کے مطابق ہو سکتا ہے تو اگلے جہان میں بھی مُردوں کا احیاء پیشگوئیوں کے مطابق ہونا ضروری ہے.بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۰۰۱ (میں) اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا (اور) بار بار رحم کرنے والا ہے (شروع کرتا ہوں).اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ۪ۙ۰۰۲ جب (نورِ) آفتاب کو لپیٹ دیا جائے گا.حَلّ لُغَات.کُوِّرَتْ کُوِّرَتْ کَوَّرَ سے مجہول کا مؤنث کا صیغہ ہے اور کَوَّرَ الْعَمَامَۃَ عَلٰی رَأْسِہٖ
Page 297
کے معنے ہوتے ہیں لَفَّھَا.اُس نے اپنے سر پر عمامہ لپیٹا اور کَــوَّرَ فُلَانًا کے معنے ہوتے ہیں صَرَعَہٗ اُس نے فلاں کو گرا دیا.اور جب کَــوَّرَ الْمَتَاعَ کہیں تو معنے ہوتے ہیں جَمَعَہٗ وَشَدَّہٗ وَ لَفَّہٗ عَلٰی جِھَۃِ الْاِسْتِدَارَۃِ اس نے اپنے مال و اسباب کو جمع کیا.اُسے باندھا اور اُسے اس طرح لپیٹا جس طرح گٹھڑی کو گول کر کے باندھتے ہیں (اقرب) اس لحاظ سےاِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ کے معنے ہوئے جبکہ سورج کو لپیٹا جائے گا یا جبکہ سُورج کو گرا لیا جائے گا.اگر سورج کے لفظ کا استعمال یہاں مجازًا سمجھ لیا جائے اور سورج سے مادی سورج مراد نہ لیا جائے بلکہ یہ سمجھا جائے کہ اس میں مجازی طور پر کسی انسان کو سورج قرار دیا گیا ہے تو اِن معنوں کا سمجھنا بالکل آسان ہو جاتا ہے.اس صورت میںاِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ میں لفظ شمس کا استعمال مجازی سمجھا جائے گا مگر یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ کُوِّرَتْ کے معنے لغۃً صرف لپیٹے جانے کے نہیں بلکہ اس کے معنے ایسے طور پر لپیٹے جانے کے ہیں جس طرح گٹھڑی کو لپیٹا جاتا ہے.پس اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ کے معنے صرف یہ نہیں کہ جب کہ سورج کو لپیٹا جائے گا بلکہ اس کے معنے یہ ہیں کہ جبکہ سورج کو گٹھڑی کی طرح باندھ دیا جائے گا اور اس کا مفہوم یہ ہو گا کہ جس طرح گٹھڑی باندھ کر الگ رکھ دیتے ہیں اسی طرح سورج کو گٹھڑی کی طرح باندھ کر الگ رکھ دیا جائے گااور اس سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں رکھا جائے گا.اسی طرح اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ کے ایک معنے حذف مضاف کی صورت میں یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ جبکہ سورج کی روشنی کو دور کر دیا جائے گا یا سورج کی روشنی کو لپیٹ دیا جائے گا اور یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ سورج کو مٹا دیا جائے گا یعنی جیسے گٹھڑی میں چیز کو باندھ دیا جاتا ہے اور وہ نظر سے اوجھل ہو جاتی ہے اسی طرح سورج بھی نظروں سے اوجھل ہو جائے گا.تفسیر.اس آیت کے جو معنے ہماری جماعت کی طرف سے کئے جاتے ہیں اُن کو جب اگلی آیات کے معنوں سے ملایا جائے تو یہ امر بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ جو معنے ہماری جماعت کی طرف سے کئے جاتے ہیں اُن میں کوئی تکلف نہیں بلکہ وہی حقیقی اور صحیح معنے ہیں.یہ بات میں نے اس لئے بیان کی ہے کہ ممکن ہے سورۂ تکویر کی اس پہلی آیت کی تفسیر بعض لوگوں کو عجیب معلوم ہو چونکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنی کتب میں اس آیت پر بحث کی ہے اور ہماری جماعت کی طرف سے بھی یہ آیت بالعموم پیش ہوتی رہتی ہے اس لئے وہ دوست جو ہماری جماعت کی باتیں سُنتے رہتے ہیں ان کوتو کوئی تکلف نظر نہیں آئے گا لیکن جو لوگ ہماری جماعت کے لٹریچر سے واقفیت نہیں رکھتے یا جن کو ہمارے سلسلہ کی باتیں سننے کا بہت کم موقع ملتا ہے ان کو شاید ان معنوں میں کوئی تکلّف محسوس ہو لیکن جب وہ ساری آیات پر غور کریں گے تو انہیں معلوم ہو گا کہ ان معنوں میں تکلّف کوئی نہیں.بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اسی حقیقت کو بیان فرمایا ہے.اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ سے مراد آنحضرت صلعم کی اتباع کو ترک کر دیا جانا یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ
Page 298
قرآن کریم میںاللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم کو سورج قرار دیا ہے ( الاحزاب :۴۷)پس جب خدا نے یہ فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جب کہ سورج کو لپیٹ دیا جائے گا تو اس کے معنے یہ تھے کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے جب رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو ترک کر دیا جائے گا.لوگ اپنی اپنی رائے پر عمل کریں گے اور رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم سے مسلمان بیزار ہو جائیں گے.قلبی طور پر نہیں بلکہ عملی طور پر وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء اور متابعت کی کوئی ضرورت نہیں سمجھیں گے اور آپ کی تعلیمات سے مُنہ پھیر لیں گے.چنانچہ یہ نظارہ آج کل ہر جگہ دیکھا جا سکتا ہے.مسلمانوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طرف بہت ہی کم توجہ ہے.قرآن پر عمل تو پہلے ہی نہیں تھا حدیث پر عمل بھی بہت حد تک اڑ گیا ہے اور اگر کچھ ہے تو وہ صرف لفظی عمل ہے حقیقت اور روح کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے اس وجہ سے رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم کا نور دنیا پر ظاہر نہیں ہوتا.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نورصرف اس بات میں نہیں کہ وضُو کرتے وقت بازو کو کہنی تک دھونا چاہیے اور سر پر مسح کرنا چاہیے بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی بتایا ہے خواہ وہ انسانی زندگی کے کسی شعبہ سے تعلق رکھنے والی بات ہو اس میں سے ہر لفظ بلکہ ہر ایک حرف پر عمل کرنا ایسی چیز ہے جس کے ذریعہ انسان کا چہرہ سورج کی طرح چمکنے لگتا اور روحانی ترقیات کی طرف اس کا قدم سرعت سے بڑھنے لگتا ہے مگر مسلمانوں کو اس بات کا کوئی احساس ہی نہیں کہ رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے نور کو وہ کس طرح سے دنیا سے اوجھل کر رہے ہیں بے شک ظاہر میں اہل حدیث کا ایک طبقہ موجود ہے جو اپنے آپ کو رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل کرنے والا قرار دیتا ہے مگر وہ بھی اُن برکات کو ظاہر نہیں کرتا جو رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم اپنے ہمراہ لائے تھے ان کا بھی زیادہ تر زور ظاہر پر ہے رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیم کے مغز اور اس کی روح کی طرف ان کی کوئی توجہ نہیں.پھر رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ دنیا کی ہدایت کے لئے جو سب سے اہم چیز لائے وہ قرآن کریم ہے مگر اہلحدیث کی ساری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ قرآن کو حدیث کے تابع کر دیں.گویا انہوںنے اگرایک چہرہ کو ظاہر کیا تھا تو دوسرے چہرہ کو انہوں نے مٹا دیا حالانکہ رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم سورج ہونے کے لحاظ سے قرآن کے بھی مظہر تھے اور حدیث کے بھی مظہر تھے مگر وہ ایک حصہ کو بالکل مٹا دیتے ہیں اور اس طرح نہیں کہا جا سکتا کہ اُن کے ذریعہ رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا نور دنیا پر ظاہر ہو رہا ہے.غرض وہ روحانی سورج جو دنیا کو روشنی پہنچانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا اس کی اتباع کو ترک کر دیا گیا ہے.سُنّیوں میں اگر کہیں قرآن پر بحث ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ حدیث کو باطل کر دیں اور صرف قرآن کی اس تفسیر کو جو اُن کے ذہنوں نے پیدا کی ہے رہنے دیں.اور اگر اہل حدیث کی طرف سے حدیث پر بحث ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ
Page 299
ہوتا ہے کہ قرآن کو راویوں کے خیالات کے تابع کر دیں اور یہ دونوں صورتیں ایسی ہیں جن سے رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم کا نور دنیا پر ظاہر نہیں ہو سکتا.بہرحال اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْکے دو معنے ہیں (۱)اتباع محمد رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کو ترک کر دیا جائے گا.اور لوگ اپنی اپنی رائے پر عمل کرنے لگیں گے.اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْسے مراد انوار محمدیہ کے نزول کا بند ہو جا نا (۲)یا یہ کہ انوار محمدؐیہ کا نزول بند ہو جائے گا اور مسلمان جن کا کام یہ تھا کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور دنیا میں زیادہ سے زیادہ پھیلائیں وہ آپ کے نور کو ظاہر کرنے کی بجائے اس کو کم کرنے کا موجب ہوں گے.اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْمیں سورج گرہن کی پیشگوئی چونکہ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ کے ایک معنے روشنی کے مٹ جانے کے بھی ہیں اس لئے اس کے یہ معنے بھی ہو سکتے ہیںکہ جب سورج اندھیر ہو جائے گا یعنی اُسے گرہن لگے گا.یہ وہی پیشگوئی ہے جس کا حدیثو ں میں بھی ذکر آتا ہے کہ اِنَّ لِمَھْدِیِّنَا اٰیَتَیْنِ لَمْ تَکُوْنَا مُنْذُ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ تَنْکَسِفُ الْقَمَرُ لِاَوَّلِ لَیْلَۃٍ مِّنْ رَمَضَانَ وَتَنْکَسِفُ الشَّمْسُ فِیْ النِّصْفِ مِنْہُ (دارقطنی کتاب العیدین باب صفة صلاة الخسوف و الکسوف و ھیئتھما) یعنے ہمارے مہدی کے دو نشان ہیں.جب سے آسمان و زمین پیدا ہوئے ہیں کسی شخص کے زمانہ میں وہ نشان ظاہر نہیں ہوئے یعنی چاند گرہن کی راتوں میں سے پہلی رات کو رمضان میں چاند گرہن لگے گا اور سورج گرہن کی تاریخوں میں سے درمیانی تاریخ کو اسی رمضان میں سورج گرہن لگے گا.گو اس سورۃ میں خالی سورج کا لفظ آتا ہے مگر حدیثوں میں سورج اور چاند دونوں کا ذکر ہے.اس کے متعلق یہ امر سمجھ لینا چاہیے کہ یہ قرآن کا محاورہ ہے اور عربی زبان کا بھی.کہ جو چیزیں آپس میں لازم ملزوم ہوں ان میں سے بعض دفعہ ایک چیز کا ذکر کر دیا جاتا ہے اور دوسری کا ذکر حذف کر دیا جاتا ہے.چونکہ ایک اور جگہ اس پیشگوئی کے ضمن میں سور ج اور چاند دونوں کا اکٹھا ذکر آتا ہے (دیکھو سورۃ قیامۃ) اس لئے یہاں صرف سورج کا ذکر کر دیا اور چاند کا ذکر چھوڑ دیاکیونکہ چاند سورج کے تابع ہے.یہ ایسی ہی بات ہے جیسے گرمی سردی کا اکٹھا ذکر کرنا ہو تو بعض دفعہ سردی کا ذکر کر دیا جاتا ہے اور مراد یہ ہوتی ہے کہ گرمی کا ذکر اس کے ساتھ ہی سمجھنا چاہیے یا گرمی کا ذکر کر دیا جاتا ہے اور سردی کا ذکر اس کے ساتھ ہی سمجھا جاتا ہے.اس جگہ چونکہ پیشگوئی کے ایک حصہ کو بیان کر دیا گیا ہے اس لئے دوسرے حصہ کی طرف خود بخود اشارہ ہو گیا اور یہ ضرورت نہ رہی کہ اس کابھی نام لے کر ذکر کیا جاتا.
Page 300
وَ اِذَا النُّجُوْمُ انْكَدَرَتْ۪ۙ۰۰۳ اور جب ستارے دُھندلے ہو جائیں گے.حَلّ لُغَات.اَلنَّجُوْمُ اَلنَّجُوْمُ: اَلنَّجْمُ کی جمع ہے اور اَلنَّجْمُ کے معنے ہیں (۱)اَلْکَوْکَبُ.ستارہ (۲)اَلنَّبَاتُ عَلٰی غَیْرِ سَاقٍ وَھُوَ خِلَافُ الشَّجَرِ بے جڑ والی بوٹی جس کو ہمارے ملک میں بیل کہتے ہیں (۳)اَلْاَصْلُ کسی چیز کی جڑ.کہتے ہیں ھُوَمِنْ نَجْمِ صِدْقٍ.وہ سچائی کی جڑ سے ہے یعنی اس کی بات سچی ہوتی ہے یا وہ اعلیٰ خاندان سے ہے.نیز کہتے ہیں لَیْسَ لِھٰذا الْحَدِیْثِ نَجْمٌ اَیْ اَصْلٌ.اس بات کی کوئی جڑنہیں یعنی حقیقت نہیں.نَـجْمٌ کی جمع اَنْـجُمٌ وَ اَنْـجَامٌ وَ نُـجُوْمٌ وَ نُـجُمٌ آتی ہے (اقرب) اِنْکَدَرَتْ اِنْکَدَرَتْ اِنْکَدَرَ سے مؤنث کا صیغہ ہے (جو کَـدَرَ سے بنا ہے) اور اِنْکَدَرَ فِیْ سَیْرِہٖ کے معنے ہوتے ہیں اَسْرَعَ وَانْقَضَّ.اس نے جلدی جلدی حرکت کی اور گر گیا.کہتے ہیں اِنْکَدَرَ یَعْدُوْا اور مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ تیزی سے دوڑا اور جب اِنْکَدَرَ عَلَیْہِ الْقَوْمُ کہیںتو معنے ہوتے ہیں اِنْصَبُّوْا.لوگ اس پر جا پڑے.اور اِنْکَدَرَتِ النُّجُوْمُ کے معنے ہوتے ہیں تَنَاثَـرَتْ ستارے جھڑ گئے (اقرب) اور کَدَرَ(یَکْدُرُ) یا کَدِرَ (یَکْدَرُ جو اِنْکَدَرَ کا اصل ہے) کَدَرَا وَکَدَارَۃً وَکُدُوْرًا وَکُدُوْرَۃً وَکُدْرَۃً.صَفَا کے مقابل کے الفاظ ہوتے ہیں یعنی وہ گدلا ہو گیا (اقرب) جیسے ہمارے ملک میں بھی کہتے ہیں کہ طبیعت مکدّر ہو گئی یا خراب ہو گئی پس ان معنوں کے اعتبار سے وَ اِذَا النُّجُوْمُ انْكَدَرَتْ کے معنے ہوں گے.جب ستارے گدلے ہو جائیں گے.اور نجوم سے مجازی طور پر وہ وجود لئے جائیں گے جن سے دنیا کو ہدایت مل رہی تھی اور جو لوگوں کے لئے راہنمائی کا مؤجب ہو رہے تھے.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جب کہ یہ نجوم گدلے ہو جائیں گے یعنی اُن کا سلسلۂ فیوض جاتا رہے گااور لوگ اُن سے ہدایت پانا بند کر دیں گے.تفسیر.النُّجُوْمُ انْكَدَرَتْ سے مراد صحابہ کی اتباع کا مفقود ہو جانا رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اَصْحَابِیْ کَالنَّجُوْم بِاَیِّھُمُ اقْتَدَیْتُمْ اِھْتَدَیْتُمْ (تشیید المبانی حدیث نمبر ۵۹) میرے صحابہؓ ستارو ں کی طرح ہیں بِاَیِّھُمُ اقْتَدَیْتُمْ اِھْتَدَیْتُمْ تم جس کے پیچھے بھی چلو گے ہدایت پاجائو گے.جب شمس سے رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم کا وجود مراد لیا گیا ہے تو نجوم سے مراد آپ کے صحابہؓ ہوئے.پس وَ اِذَا النُّجُوْمُ انْكَدَرَتْ کے یہ معنے ہوئے کہ نہ صرف رسول کریم صلے اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کی اتباع مفقود ہو جائے گی بلکہ صحابہ کی اتباع بھی جاتی رہے
Page 301
گی اور اُن کے بتائے ہوئے علوم متروک ہو جائیں گے.چنانچہ ہم دیکھتے ہیں اس زمانہ میں ایسا ہی نظارہ نظر آ رہا ہے لوگ جب بھی کوئی مثال پیش کریں گے بجائے اس کے کہ صحابہؓ کا ذکر کریں وہ کہیں گے ہٹلر نے یوں کہا ہے یا نپولین نے یوں کہا ہے یا ابراہیم لنکن نے یوں کہا ہے.لیکن پُرانے زمانہ میں لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ ابو بکرؓ نے یوں کہا ہے.عمرؓ نے یوں کہا ہے.عثمان ؓنے یوں کہا ہے.علیؓ نے یوں کہا ہے.غرض مسلمانوں میں صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی اہمیت بالکل جاتی رہی ہے.انگریزی میں کہتے ہیں کہ کسی قوم کی زندگی اس کی ٹریڈیشن TRADITIONپر چلتی ہے یعنی قوم کا ہر فرد جب تک اپنے دل میں یہ احساس نہ رکھتا ہو کہ اُس نے اپنی قومی روایات کو زندہ رکھنا ہے اس وقت تک قوم کی زندگی کی امید نہیں رکھی جا سکتی.زندہ قوموں کا یہی دستور ہے کہ اُن کا ہر فرد اپنے باپ دادا کے نیک افعال کو زندہ رکھنے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے باپ نے یوں کیا تھامیرا دادا اس طرح کیا کرتا تھا.جب تک قوم اس روح کو اپنے اندر محفوظ رکھتی ہے اس کی زندگی کی گھڑیاں لمبی ہوتی چلی جاتی ہیں اور جب یہ رُوح مر جاتی ہے تو قوم بھی اس کے ساتھ ہی مر جاتی ہے.پس وَ اِذَا النُّجُوْمُ انْكَدَرَتْکے یہ معنے ہوئے کہ صحابہؓ کی خوبیاںاور اُن کے کمالات عمل کے لحاظ سے مٹ جائیں گے جس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ قومی ٹریڈیشن TRADITION یعنی قومی برتری کی روایات بھی قوم کے حافظہ سے جاتی رہیں گی اور وہ روایات زندہ نہیں رہیں گی جن سے اخلاق ترقی کرتے اور امنگوں میں وسعت پیدا ہوتی ہے.جب قوم کے افراد کے سامنے بار بار یہ بات آتی رہے کہ ہمارے باپ دادا اپنے اندر بہت بڑی خوبیاں اور کمالات رکھتے تھے تو وہ خود بھی ترقی کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اگر انہیں کہا جائے کہ تمہارے باپ دادا بالکل نالائق تھے.انہیں ترقی سے کوئی لگائو نہیں تھا تو آگے بڑھنے کی قابلیت اُن میں مفقود ہو جاتی ہے.اسلام اور مسلمانوں پر سب سے بڑی تباہی اسی وجہ سے آئی ہے کہ اُن کی شاندار قومی روایات طاقِ نسیان پر رکھ دی گئی ہیں اور ماضی سے اُن کا تعلق مٹ گیا ہے.اور صحابہؓ اور اُن کے نقشِ قدم پر چلنے والے لیڈروں کی خوبیاں مسلمانوں کی نظروں سے اوجھل ہو گئیں.اس ٹریڈیشن کے تباہ کرنے میں یوروپین لوگوں کی لکھی ہوئی تاریخوں نے خصوصیت سے حصہ لیا ہے.کوئی مسلمان بادشاہ ایسا نہیں جس پر انہوں نے الزام نہ لگایا ہو اور اُسے بُری سے بُری اور بھیانک سے بھیانک صورت میں لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش نہ کی ہو.اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہر مسلمان طالب علم جو اُن تاریخوں کو پڑھتا ہے یہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ اس کے آباء میں کوئی خوبی نہ تھی وہ ہر خوبی دوسروں کی طرف منسوب کرتا اور ہر نقص اپنے بزرگوں کی طرف منسوب کرنا شروع کر دیتا ہے.اس طرح قومی ترقی کی جڑ کھوکھلی ہو کر رہ جاتی ہے کیونکہ بغیر ٹریڈیشن کے.بغیر قومی روایات کو زندہ رکھنے
Page 302
کے دنیا میں کوئی قوم زندہ نہیں رہ سکتی.آسان سے آسان طریق کسی قوم کو تباہ کرنے کا یہ ہے کہ اُسے اپنی پچھلی تاریخ سے بدظن کر دیا جائے.اگر اُسے اپنی پچھلی تاریخ سے بدظن کر دیا جائے تو وہ اُجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْاَرْضِ مَالَھَا مِنْ قَرَارٍ (ابراہیم:۲۷ )کا مصداق بن جاتی ہے اور کبھی زندہ نہیں رہ سکتی.یوروپین لوگوں نےاس آسان حربہ سے کام لیا اور تمام اسلامی تاریخ کو انہوں نے بگاڑ کر رکھ دیا.بڑے بڑے مسلمان بادشاہوں کا ذکر کریں گے تو کہیں گے فلاں میں یہ نقص تھااور فلاں میں وہ نقص تھا.اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ وہ اس کا نام تحقیقات رکھتے ہیں اور دعوے سے کہتے ہیں کہ تحقیق کے بعد یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ فلاں مسلمان بادشاہ ایسا تھا حالانکہ وہ سراسر جھوٹ ہوتا ہے.اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج کسی مسلمان سے پوچھ کر دیکھو اُسے اپنے اسلاف میں کوئی خوبی نظر ہی نہیں آئے گی.وہ کہے گا محمود غزنوی ڈاکو تھا اورنگزیب ظالم تھا.فلاں ایسا تھا اور فلاں ایسا تھا.گویا عیب شماری اور الزام تراشی ہی اُن کا کام رہ گیا ہے.اُن کے اندر یہ حس ہی نہیں رہی کہ وہ کسی کی خوبیوں کو بھی دیکھ سکیں.اس نقص کی وجہ سے مسلمانوں میں ٹریڈیشن کا وجود ہی باقی نہیں رہا اور اُن کی قومی ترقی کی جڑ کو کاٹ کر رکھ دیا گیا ہے.وہ مسلمانوں کو اپنے آباء کے خلاف مشتعل کرنے کے لئے ایسے ایسے حربوں سے کام لیتے ہیں جو قطعاً کوئی شریف انسان استعمال نہیں کر سکتا.مثلاً کسی مسلمان بادشاہ کا ذکر کریں گے تو کہیں گے کہ وہ تو شراب پیتا تھا اور وہ اِس الزام کا ذکر محض اس لئے کریں گے کہ مسلمانوں کی طبیعتوں میں جوش پیدا ہو جائے اور وہ اُسے بُرا بھلا کہنے لگ جائیں.حالانکہ یہ الزام لگانے والے وہ ہیں جو خود دن رات شرابیں پیتے اور کئی قسم کے ناروا افعال کرتے رہتے ہیں مگر یہ شرابی قوم اپنے افعال کی طرف تو نہیں دیکھتی اور کسی مسلمان بادشاہ کا ذکرآ جائے تو اس کے متعلق لکھ دیتی ہے کہ وہ شراب پیتا تھا.محض اس لئے کہ مسلمان بھڑک اٹھیں اور وہ اس سے متنفّر ہو جائیں حالانکہ یہ قوم وہ ہے جس کا ہر فرد شراب پیتا ہے جس کا بادشاہ بھی شراب پیتا ہے اور جس کا وزیراعظم بھی شراب پیتا ہے.چرچل بھی شراب پیتا ہے اور روزویلٹ بھی شراب پیتا ہے.مگر وہ مسلمان بادشاہ کے کے متعلق یہ ضرور ذکر کریں گے کہ وہ شراب پیتا تھا چلو ہم نے مان لیا کہ وہ شراب پیتا تھا مگر تم تو وہ ہو جو ہمیں اُس مسلمان بادشاہ سے متنفّر کر کے اُن لوگوں کی خوبیوں کا ہمیں قائل کرنا چاہتے ہوجو اس سے ہزاروں گُنے زیادہ شراب پیا کرتے تھے اورہزاروں گُنا زیادہ بُرے افعال کیا کرتے تھے.غرض فرماتا ہے کہ وَاِذَاالنُّجُوْمُ انْکَدَرَتْ یعنی تاریخ اسلامی مکّدر ہو جائے گی.اُس کی خوبیاں مٹا دی جائیں گی اور یُوں معلوم ہو گا کہ نجوم میں انکدار واقع ہو گیا ہے.(۲) نَجْمٌ کے ایک معنے چونکہ اَصْلٌ کے بھی ہیں اس لئے اَلنُّجُوْمُ انْکَدَرَتْ کے معنے یہ بھی ہیں کہ جڑیں خراب
Page 303
ہو جائیں گی یعنی قومی برتری کے جو اصول رائج ہیں کہ فلاں آدمی فلاں قوم سے ہے اور فلاں آدمی فلاں قوم سے یہ مٹ جائیں گے چنانچہ اس زمانہ میں نسلی برتری کا احساس بالکل مٹا دیا گیا ہے.یورپ میں تو یہ امتیاز بالکل رہاہی نہیں ہمارے ملک میں بھی آہستہ آہستہ یہ احساس مٹتا چلا جا ر ہا ہے اور جو لوگ خاندانی سمجھے جاتے تھے اُن کا رسوخ اب مفقود ہو رہا ہے.پس اس کے ایک معنے یہ بھی ہیں کہ قومی برتری کے جو عام قواعد دنیا میں رائج ہیں وہ اُس وقت نہیں رہیں گے چنانچہ دیکھ لو آج کل اچُھوت اقوام کو اُبھارنے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں وہ بھی اسی لئے ہیں کہ ان نسلی امتیازات کو بالکل مٹا دیا جائے.اِذَا النُّجُوْمُ انْكَدَرَتْمیں اس امر کی پیشگوئی کہ علماء اور امراء کا اثر جاتا رہے گا (۳)وَ اِذَا النُّجُوْمُ انْكَدَرَتْ کے یہ بھی معنے ہو سکتے ہیں کہ اُس زمانہ میں علماء اور امراء دونوں کا اثر جاتا رہے گا.قوم کی راہنمائی کی باگ دوڑ انہی دوطبقوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے.امراء سیاسی راہنمائی کرتے ہیں.اور علماء مذہبی راہنمائی کرتے ہیں پس وَ اِذَا النُّجُوْمُ انْكَدَرَتْ کے یہ معنے ہوئے کہ پبلک کا تعلق علماء اور امراء دونوں سے کمزور ہو جائے گا.امراء کا اثر دنیوی لوگوں پر سے اُٹھ جائے گا اور علماء کا اثر دینی میلان رکھنے والوں پر سے اٹھ جائے گا.گویا امراء کی طاقت بھی ٹوٹ جائے گی اور علماء کی طاقت بھی ٹوٹ جائے گی.اِذَا النُّجُوْمُ انْكَدَرَتْمیں شہب کے گرنے کی طرف اشارہ (۴)اِنْکَدَرَتْ کے ایک معنے تَنَاثَرَتْ کے بھی ہیں پس اس معنے کے اعتبار سے جب ہم پہلی آیت کے ساتھ ملاتے ہیں تو چونکہاِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ کے ایک معنے یہ بھی ہیں کہ سورج اور چاند کو گرہن لگے گا اس لئے اس مناسبت سے اِذَا النُّجُوْمُ انْكَدَرَتْ کے یہ معنے ہوں گے کہ موعود زمانہ میں شہب بڑی کثرت سے گریں گے چنانچہ یہ پیشگوئی بھی بڑی واضح طور پر پوری ہوئی اور ۲۸؍نومبر ۱۸۸۵ء کو اس کثرت سے شُہب گرے کہ فضاء آسمان میں ہر طرف شعلے جلتے ہوئے نظر آتے تھے اور یورپ اور امریکہ اور ایشیا کی اخبارات نے اس نظارہ قدرت کو عجوبہ سمجھ کر بہت کچھ لکھا اور حیرت ظاہر کی(آئینہ کمالات اسلام روحانی خزائن جلد ۵ صفحہ ۱۱۰.Patrick Moor The Guinness Book of Astronomy 5th edition pg.132).اگر ہم شمس کے روحانی معانے کریں تو نُـجُوْم کے بھی روحانی معنے کریں گے اور اگر شمس سے ظاہری سورج مراد لیا جائے تو نجوم کے انکدار سے بھی شُہب کا کثرت سے گرنا مراد لیا جائے گا.غرض وَ اِذَا النُّجُوْمُ انْكَدَرَتْ کے یہ معنے ہوئے (۱)کثرت سے شُہب کی بارش ہو گی (۲)یا یہ کہ صحابہؓ کی اتباع بھی جاتی رہے گی.اُن کے بتائے ہوئے علوم متروک ہو جائیں گے یا یہ کہ اُن کی اتباع نیکی اور تقویٰ میں لوگ چھوڑ دیں گے (۳)یا یہ کہ جو لوگ
Page 304
خاندانی سمجھے جاتے تھے اُن کا رسوخ جاتا رہے گا (۴)یا امراء کا اثر عوام پر سے اُٹھ جائے گا (۵)یا یہ کہ علماء مذہبی کا رسوخ مٹ جائے گا.یہ سب علامات ایسی ہیں جو آج کل پوری ہو چکی ہیں.وَ اِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ۪ۙ۰۰۴ اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے.حَلّ لُغَات.اَلْجِبَالُ اَلْجِبَالُ اَلْجَبَلُ کی جمع ہے اور اَلْجَبَلُ کے معنے ہیں کُلُّ وَتَدٍ فِی الْاَرْضِ عَظُمَ وَطَالَ.یعنی اونچے ٹیلے کو جَبَل کہتے ہیں اور جِبَالَ خِلَافُ السَّاحِلِ کو بھی کہتے ہیں.یعنی اندرونِ ملک کو.اور جَبَل کے ایک معنے سَیِّدُ الْقَوْمِ وَعَالمُھُمْ کے بھی ہوتے ہیں چنانچہ عرب کہتے ہیں فُلَانٌ جَبَلَ قَوْمِہٖ کہ فلاں اپنی قوم کا جبل ہے یعنی اس قوم کا سردار اور بڑا عالم ہے.(اقرب) سُیِّرَتْ سُیِّرَتْ سَیَّرَ سے مؤنث کا مجہول کا صیغہ ہے اور سَیَّــرَ کے معنے ہوتے ہیں جَعَلَہٗ سَائِرًا.اس کو چلایا اور سَیَّرَ الْجُلَّ عَن ظَھْرِ الدَّآبَّۃِ کے معنے ہوتے ہیں اَلْقَاہُ.جانور کا جھول اتار کر پیٹھ پر سے نیچے پھینک دیا اور سَیَّرَ الْمَثَلَ کے معنے ہوتے ہیں جَعَلَہٗ یَسِیْرُ بَیْنَ النَّاسِ.کسی محاورہ کو پھیلا دیا اور سَیَّرَہٗ مِنْ بَلَدِہٖ کے معنے ہیں اَخْرَجَہُ وَاَجْلَاہُ.اس کو اپنے شہر سے نکال دیا اور جلاوطن کر دیا (اقرب)پس وَ اِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ کے معنے ہوں گے (۱)جب پہاڑ چلائیں گے (۲)جب علماء اور لیڈر اپنے ملکوں سے نکالے جائیں گے.تفسیر.اِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْکی پیشگوئی کے مطابق پہاڑوں کا اڑایا جانا اس آیت کے معنے یہ ہیں کہ جب پہاڑ اپنی جگہ سے چلائے جائیں گے یعنی پہاڑوں کو اُڑا اُڑا کر رستے بنائےجائیں گے.اس صورت میں سُیِّـرَتْ کے لفظ کا استعمال ایسا ہی سمجھا جائے گا جیسے کہتے ہیں پرنالے چلتے ہیں حالانکہ پرنالہ نہیں چلتا بلکہ پانی چل رہا ہوتا ہے.اسی طرح سُیِّرَتْ الْجِبَالُ کے یہ معنے لئے جائیں گے کہ پہاڑوں کو ڈائنامیٹ سے اُڑا اُڑا کر راستے تیار کئے جائیں گے چنانچہ اس کا ثبوت ہر پہاڑ پر موجود ہے پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر اور ڈائنامیٹ سے اُڑا اُڑا کر سڑکیں اور راستے بڑی کثرت سے تیار کئے گئے ہیں.اور ڈلہوزی.شملہ.مری.کشمیر.منصوری وغیرہ تمام پہاڑوں پر یہ راستے دیکھے جا سکتے ہیں.پس اِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ کے یہ معنے ہوئے کہ پہاڑوں پر رستے تیار کئے جائیں گے جن پر لوگ چلیں گے گویا ان معنوں کی صورت میں یہاں سیّر کی نسبت مقام کی جگہ صاحب مقام کی
Page 305
طرف سمجھی جائے گی یعنی لفظاً تو یہ کہا گیا ہے کہ پہاڑ چلائیں جائیں گے مگر مراد یہ ہے کہ پہاڑوں پر لوگ کثرت سے چلیں گے کیونکہ پہاڑوں پر اچھے راستے تیار ہو جائیں گے.موجودہ زمانہ میں اس کثرت سے پہاڑ اُڑائے گئے ہیں کہ کوئی حد ہی نہیں رہی.شاید ہی کوئی پہاڑ ایسا رہ گیا ہو جہاں سڑکیں اور رستے تیار نہ کر لئے گئے ہوں.ورنہ ہر پہاڑ پر چلنے کے لئے راستے بن گئے ہیں.پہاڑ کے نیچے ڈائنامیٹ رکھ دیتے ہیں اور وہ فوراً ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے.پھر لڑائیوں میں بھی کثرت سے پہاڑ اڑائیں جاتے ہیں.اوپر دشمن کی فوج موجود ہوتی ہے اور نیچے بارود رکھ کر اُسے اُڑا دیا جاتا ہے پہلے زمانوں میں تو اتنا بارود ہی نہیں تھا کہ پہاڑوں کو اڑایا جا سکتا.ضمناً اس آیت میں بارود کی کثرت کی طرف بھی اشارہ پایا جاتا ہے کیونکہ سڑکیں وغیرہ تیارنہیں ہو سکتی تھیں جب تک ڈائنامیٹ نہ ہوتا.اگر ڈائنا میٹ نہ ہوتا تو چٹانوں کا اڑانا بڑامشکل ہوتا.اسی طرح بعض مشینیں ایسی ایجاد ہو چکی ہیں جو رستوں کو بالکل صاف کر دیتی ہیں.پس ضمنًا اس آیت میں بارود کی کثرت اور ایسی مشینری کی ایجاد کی طرف بھی اشارہ تھا جن سے پہاڑوں پر سڑکیں وغیرہ تیار ہو سکیں.اِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْمیں علماء اور سادات قوم کو ملکوں سے نکالے جانے کی پیشگوئی (۲)جَبَلٌ کے ایک معنے چونکہ سَیِّدُ الْقَوْمِ وَعَالِمُھُمْ کے بھی ہوتے ہیں اس لئے وَاِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ کے یہ معنے بھی ہیں کہ علماء و ساداتِ قوم کو ملکوں میں سے نکال دیا جائے گا.اس کی مثال بھی پہلے کہیں نظر نہیں آتی.موجودہ زمانہ ہی ہے جس میں ایک طرف تمام رُوس سے ایسے مذہبی لوگوں کو نکال دیا گیا ہے جو مذہب کو سیاست پر مقدم رکھتے ہیں.دوسری طرف ترکوں نے مذہب پر ایسا ہاتھ صاف کیا ہے کہ حکم دے دیا ہےکہ اگر نماز پڑھی جائے تو ترکی میں ہی پڑھی جائے.قرآن پڑھا جائے تو ترکی میں پڑھا جائے اور اگر کوئی شخص ایسا نہ کرے تو وہ اُسے اپنے ملک سے نکال دیتے ہیں یا قید کر دیتے ہیں.اگلی آیات پر بحث تو بعد میں آئے گی انہی تین آیات پر غور کر کے دیکھو اور سوچو کہ کیا اس زمانہ سے قبل دنیا میں کسی زمانہ میں بھی ان باتوں کا اجتماع ہوا ہے؟ اگر دنیا کی ساری تاریخ کو جمع کر لیا جائے تب بھی کسی زمانہ میں ان علامات کا تیسرا حصہ تو کیا دسواں حصہ بھی نظر نہیں آئے گا.سورج چاند کو گرہن لگنا.شہب کا کثرت سے گرنا اور پھر قومی روایات کا مٹ جانا یہ اتنی بیّن علامات ہیں کہ اس سے پہلے کسی زمانہ میں نظر نہیں آتیں.چھ ہزار سال تو کیا اگر ایک لاکھ سال کی تاریخ کو بھی جمع کر لیا جائے تو کہیں یہ دکھائی نہیں دے گاکہ مغلوب اقوام کی قومی روایات کو اس طرح مٹا دیا گیا ہوجس طرح آج مٹایا گیا ہے.یورپ کا ہر جاہل.شرابی.ظالم بادشاہ اچھی شکل میں پیش کیا جاتا ہے اور ہر
Page 306
اچھے اخلاق کا مسلمان بادشاہ کریہہ شکل میں دکھا یا جاتا ہے اور مغربی لوگوں کے ہاتھ میں تعلیم ہونے کی وجہ سے مسلمان بھی اسی خیال کے ہو گئے ہیں.یہ تو پہلے زمانوں میں بھی نظر آئے گا کہ زید اپنے اَسْلاف کے کارناموں کو بُھول گیا یا بکر اپنے آباء کی خوبیوں سے غافل ہو گیا مگر یہ کہیں دکھائی نہیں دے گا کہ قوم کی قوم اپنی شاندار قومی روایات کو نہ صرف بُھلا دے بلکہ اپنے اَسْلاف کی خوبیاں بھی اُسے عیب نظر آنے لگ جائیں.آج لاکھوں لوگ یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ فلاں مسلمان بادشاہ ایسا گندہ تھا اور فلاں مسلمان بادشاہ ایسا خبیث تھا حالانکہ اُن سے زیادہ گندے اور ان سے زیادہ خبیث بادشاہوں کی وہ تعریف کر رہے ہوتے ہیں.وُہ یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ محمود غزنوی ایسا تھا مگر وہ اتنا نہیں سوچتے کہ وہ خود جن کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں وہ اُن سے زیادہ گندے اور ناپاک ہوتے ہیں.کوئی مسلمان بادشاہ تو چوری چھپے شراب پیتا ہو گا مگر یہ جن کی تعریف کرتے ہیں وہ رات دن شرابیں پیتے تھے.اگر شراب پینا نقص ہے تو یہ اسلامی نقطۂ نگاہ سے نقص ہے عیسائیت کے نقطہ ءنگاہ سے تو یہ ایک اچھا کام ہے پس انہیں تو چاہیے تھا کہ وہ خوش ہوتے کہ ایک مسلمان بادشاہ بھی شراب پینے پر مجبور ہوا مگر وہ اُلٹا اُس کو بُرا بھلا کہتے ہیں جس کی غرض سوائے اس کے کچھ نہیں ہوتی کہ مسلمانوں کے دلوں میں اپنے بادشاہوں کی نسبت نفرت اور حقارت کے جذبات پیدا ہوں حالانکہ انہیں اس سے کیا واسطہ ہے کہ کوئی شراب پیتا تھا یا نہیں.اُنہیں تو نظامِ حکومت کے لحاظ سے تبصرہ کرنا چاہیے کہ اس نے حکومت سے تعلق رکھنے والے کام کس طرح سرانجام دیئے.میں گزشتہ دنوں لاہور میں تھا کہ ایک شخص نے مجھ سے سوال کیا کہ محمود غزنوی کے فلاں فلاں افعال آیا اسلام کے مطابق تھے یا اس کی تعلیم کے خلاف تھے؟ میں نے اُس سے کہا کہ ان امور کا تعلق مذہبی نقطۂ نگا ہ کے ساتھ ہے لیکن تم جس وقت کسی مسلمان بادشاہ کو بُرا کہتے ہو تو تمہارا منشاء یہ ہوتا ہے کہ تم یہ ثابت کرو کہ یہ مُسلمان بادشاہ تو بُرا تھا لیکن فلان یوروپین بادشاہ بہت اچھا تھا حالانکہ اُس یوروپین بادشاہ میں بھی ہزاروں عیوب ہوتے ہیں.پس یہ طریق درست نہیں تمہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ محمود غزنوی نے جو اخلاق دکھائے وہ اُس زمانہ کے اوربادشاہوں کے مقابلہ میں کیسے تھے.اگر اپنے زمانہ کے بادشاہوں کے مقابلہ میں اُس نے اعلیٰ درجہ کے اخلاق دکھائے ہیں تو گو اس میں بعض کمزوریاں بھی ہوں پھر بھی تاریخی نقطۂ نگا ہ سے وہ ایک اعلیٰ درجہ کا بادشاہ سمجھا جائے گا اور اُس کا مقابلہ موجودہ زمانہ کے کسی بادشاہ سے نہیں کیا جائے گا.اس کی ایسی ہی مثال ہے کہ ایڈیسن نے کئی ایجادات کی تھیں اس کے بعد ایجادات کا سلسلہ ایڈیسن کی ایجادات سے کئی گناہ بڑھ گیا مگر اس سے ایڈیسن کی عزت میں کمی نہیں آسکتی.اس لئے کہ اپنے زمانہ میں اُس نے ایسا کام کیا جو نہایت شاندا ر تھا.اسی طرح اگر محمود غزنوی نے اپنے زمانہ کے بادشاہوں
Page 307
کے مقابلہ میںاعلیٰ درجہ کے اخلاق دکھائے ہیں تو بہرحال وہ ایک قابلِ تعریف بادشاہ سمجھا جائے گا اور اسی نقطۂ نگاہ سے ہمیں اس کے افعال کو دیکھنا پڑے گا.غرض قومی روایات کے گدلا ہو جانے کی مثال موجودہ زمانہ میں اتنی واضح اور اس قدر نمایاں ہے کہ قومی طور پر اس سے پہلے کسی زمانہ میں یہ مثال نظر نہیں آتی.اسی طرح علماء اور امراء کا زور ٹوٹ جانا بھی اتنا واضح ہے کہ پہلے کسی زمانہ میں اس کی مثال نہیں مل سکتی.روس سے مذہب پر سختی سے پابند ہونے والے علماء کو نکال دیا گیا.ٹرکی سے ان کو نکال دیا گیا.جرمنی اور اٹلی سے انہیں نکال دیا گیا.اسی طرح بعض اور ممالک میں اُن سے یہ سلوک کیا گیا اور مقامِ عزت سے اتار کر اُنہیں اس طرح نیچے پھینک دیا گیا جس طرح جانور کا جھول اتار کر پھینک دیا جاتا ہے.غرض یہ علامات جو ان تین آیات میںبیان کی گئی ہیںاور وہ علامات جو اگلی آیا ت میں بیان ہیں اگر ان سب کو بیان کیا جائے تو یقیناً کسی زمانہ میں یہ باتیں اکٹھے طور پر نظر نہیں آئیں گی.بلکہ اگر یہ سب باتیں ایک نقشہ کے طور پر شائع کر دی جائیں اور ساتھ ہی یہ انعام مقرر کر دیا جائے کہ اگر کوئی شخص اِن علامات کو گزشتہ زمانہ پر چسپاں کر کے دکھا دے تو اُسے لاکھ یا دو لاکھ روپیہ بطور انعام دیا جائے گا تب بھی کوئی شخص یہ ثابت نہیں کر سکے گا کہ پہلے کسی ایک زمانہ میں یہ علامات پوری ہو چکی ہیں دنیا کے کسی مؤرخ کے سامنے ان علامات کو رکھ دو اور پھر اس سے پوچھو کہ یہ علامات کس زمانہ پر صادق آتی ہیں تو وہ فوراً کہہ اٹھے گا کہ یہ تو اسی زمانہ کی علامات بیان کی جا رہی ہیں پہلے کسی زمانہ میں ایسے حالات پیدا نہیں ہوئے.غرض ہر شخص کی انگلی اِن آیات کو پڑھ کر موجودہ زمانہ کی طرف ہی اٹھے گی کسی اور زمانہ کی طرف نہیں اُٹھ سکتی اور یہی رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان سورتوں میں ایک یوم القیامۃ کا ایسا واضح نقشہ کھینچا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص اُس یوم القیامۃ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے تو وہ اِن سورتوں کو پڑھ لے.وَ اِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ۪ۙ۰۰۵ اور جب دس مہینے کی گابھن اونٹنیاں اوارہ چھوڑ دی جائیں گی.حَلّ لُغَات.عِشَارُعِشَارُ عُشَرَاءُ کی جمع ہے.عربی زبان میں مفردات میں عُشَرَاءُ کی اپنے وزن میں کوئی نظیر نہیں.صرف نُفَسَائُ ہی ایک لفظ ہے جو اس کے ہم وزن ہے گویا عُشَرَائُ اور نُفَسَائُ دو ہی لفظ اس وزن میں پائے جاتے ہیں تیسرا کوئی لفظ ان وزنوں کے لحاظ سے عربی زبان میں نہیں ہے.لکھا ہے اَلْعُشَرَاء
Page 308
کَنُفَسَائَ وَلَا ثَالِثَ لِھٰذَیْنِ الْاِسْمَیْنِ (اقرب) عِشَار اُن اونٹنیوں کو کہتے ہیں جن کے حمل پر دس مہینے گزر جائیں یا آٹھ مہینے گزر جائیں اکثر لوگوں کے نزدیک عشار انہی اونٹنیوں کو کہتے ہیں جن کے حمل پر دس مہینے گزر جائیںمگر بعض نے کہا ہے کہ جن کے حمل پر آٹھ مہینے گذر جائیںان کو بھی عِشَار کہتے ہیں (اقرب) اس لفظ کی بناوٹ سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ جن لوگوں کا خیال زیادہ صحیح ہے جو عشار دس ماہ کی گابھن اونٹنیوں کو کہتے ہیں.اُن اونٹنیوں کے گلّہ کو بھی عِشَار کہتے ہیں جن میں سے بعض بچہ جَن چکی ہوں اور بعض کا بچہ قریب میں ہونے والا ہو.(اقرب)گویا عِشَار دس ماہ کی گابھن اونٹنیوں کو بھی کہتے ہیں اور اونٹنیوں کا وُہ گلّہ بھی عِشَار کہلاتا ہے جن میں سے بعض بچہ جن چکی ہوں اور بعض انتظار کر رہی ہوں.عُطِّلَتْ عُطِّلَتْ عَطَّلَ سے مجہول مؤنث کا صیغہ ہے اور عَطَّلَ الْاِبِلَ کے معنے ہوتے ہیں خَلَّاہُ بِلَارَاعٍ یعنی بغیر گلّہ بان اور چرواہے کے اُونٹ کو چھوڑ دیا وَ کُلُّ مَاتُرِکَ ضِیَاعًا فَقَدْ عُطِّلَ.اور ہر وہ چیز جسے یونہی ضائع ہونے کے لئے چھوڑ دیا جائے اس کے لئے عَطَّلَ کا لفظ آتا ہے (اقرب) پس وَاِذَا الْعِشَارُعُطِّلَتْ کے معنے یہ ہوئے (۱)جبکہ دس ماہ کی گھابن اُونٹنیوں کو یونہی چھوڑ دیا جائے گا یعنی خواہ وہ مریں یا جئیں اُن سے کوئی تعلق نہیں رکھا جائے گا (۲)ایسی اونٹنیوں کے گلّوں کو جن میں سے بعض بچہ دے چکی ہوں اور بعض ابھی بچہ دینے والی ہوں چھوڑ دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں.یہ چاہے مریں یا رہیں ہمارا ان سے کوئی واسطہ نہیں.تفسیر.اِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْمیں لفظ عشار استعمال کرنے کی وجہ قرآن کریم عرب میں نازل ہوا ہے اس لئے قرآن کریم میں عرب کی ضروریات اور اہلِ عرب کے جذبات کو سب سے مقدّم رکھا گیا ہے تاکہ پہلے وہ خود قرآن کریم کو اچھی طرح سمجھ لیں اور پھر اُسے دنیا میں پھیلائیں.جو قوم الہامِ الٰہی کی اوّلین مخاطب ہوتی ہے اس کے محاورات اور اس کے جزبات وغیرہ کو کلام میں مقدم رکھا جاتا ہے کیونکہ اگر وہ اس کلام کو سمجھے گی نہیں تو اُسے پھیلائے گی کس طرح.یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ عرب میں سواری اور غذا دونوں چیزیں اونٹ سے وابسطہ تھیں اونٹ ہی پر وہ سواری کرتے تھے اور اُونٹنی کا دودھ ہی غذا کے طور پراستعمال کرتے تھے.اسی طرح اونٹ کا گوشت کھایا کرتے تھے اور ان تینوں باتوں کے لحاظ سے دس ماہ کی گھابن اونٹنی خواہ وہ بچہ جَن چکی ہویا بچہ جَننے والی ہو ان کی نگاہ میں بہت بڑی وقعت رکھتی تھی اس لئے کہ بچہ جَننے والی نہ صرف خود سواری کے قابل ہوتی تھی بلکہ اس کے متعلق یہ امید بھی ہوتی تھی کہ اس کا جو بچہ پیدا ہو گا وہ بھی سواری کے یا غذا کے کام آئے گا.پھر وہ اونٹنی کا دُودھ پیتے تھے اور دُودھ کے لحاظ سے بھی دس ماہ کی گھابن اونٹنی کو وہ بہت قیمتی سمجھتے تھے کیوں کہ جانتے تھے کہ یہ عنقریب بچہ دے گی اور
Page 309
ہم اُس کا دُودھ خُوب پئیں گے.پھر وہ گوشت کھایا کرتے تھے اس لحاظ سے دس ماہ کی گابھن اونٹنی بہت اعلیٰ خیال کی جاتی تھی کیونکہ چھوٹے بچے کا گوشت بہت اچھا ہوتا ہے.پشاور کی تجارت کا ایک بڑا حصہ دُنبہ کے بچہ کے گوشت سے وابستہ ہے وہ دو ماہ کا دُنبہ ذبح کر کے اس کا گوشت بیچتے ہیں اور لوگ دُور دُور سے اس دنبہ کا گوشت چکھنے کو پشاور جاتے ہیں.بکری کے چھوٹے بچے کا گوشت بھی بہت مزیدار ہوتا ہے.غرض وہ ایسی اونٹنی کو بہت قیمتی سمجھتے تھے اور خیال کرتے تھے کہ ہم اونٹنی کا دودھ پئیں گے اور بچے کا گوشت کھائیں گے.لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ایک زمانہ آنے والا ہے جب ایسی اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے لُغت کے لحاظ سے عَطَّلَ کے معنے یہ ہوئے کہ کسی چیز کو ضائع ہونے کے لئے چھوڑ دیا جائے اور اس سے کسی قسم کا واسطہ نہ رکھا جائے.اس لحاظ سے عُطِّلَتْ کے دو ہی معنے ہو سکتے ہیںکہ (۱)اونٹ کو بیکار کرنے والی سواریاں نکل آئیں گی جس سے ایسی اونٹنیوں کی قیمت بھی کہ دس ماہ سے گابھن ہوں اور جلد بچہ دینے والی ہوں گر جائے گی اور لوگ اُن کو چھوڑ دیں گے (۲)یا یہ کہ اس قدر تیز سواریاں نکل آئیں گی کہ اُن کی وجہ سے ہر قسم کی غذائیں عرب میں پہنچنے لگیں گی اور اونٹ کے دودھ کی چنداں ضرورت نہ رہے گی جس کی وجہ سے جنی ہوئی اور جننے کے قریب پہنچی ہوئی اونٹنی کی قدر پہلے جیسی نہ رہے گی چنانچہ ہم دیکھتے ہیں اس زمانہ میں یہ دونوں باتیں پوری ہو چکی ہیں.سواری کے لئے دخانی جہاز.ریل.موٹر اور ہوائی جہاز ایجاد ہو چکے ہیں اور ان نئی ایجادات کی وجہ سے عرب میںجہاں اونٹوں پر سفر کیا جاتا تھا وہاں اب موٹروں پر سفر کیا جاتا ہے.جب شروع شروع میں عرب میں موٹریں جاری کی گئیں تو بدئووں نے بغاوت کر دی کہ اس طرح ہماری تجارت کو نقصان ہو گا مگر آخر موٹریں ہی جاری رہیں اور اونٹ کی سواری متروک ہو گئی چنانچہ اب مکّہ میں جانے والے موٹروں پر سفر کر کے ہی جاتے ہیں.مولوی ثناء اللہ صاحب نے ایک دفعہ اعتراض کیا تھا کہ مکّہ میں تواب تک ریل نہیں گئی حالانکہ ریل کیا اور موٹر کیا مطلب تو یہ تھا کہ اونٹ کی سواری جاتی رہے گی اور اس کی بجائے ایسی نئی سواریاں نکل آئیں گی جن کو لوگ زیادہ ترجیح دیں گے چنانچہ موٹروں نے اونٹ کی سواری کی اہمیت بالکل گرا دی ہے.ریل تو مقررہ وقت پر چلتی ہے مگر موٹریں ہر وقت چل سکتی ہیں اس لئے جہاں موٹر چلتی ہے وہاں دوسری سواریاں بالکل رہ جاتی ہیںکیوں کہ وہ ہر وقت چل سکتی ہے غرض اس پیشگوئی کو اللہ تعالیٰ نے اس رنگ میںپورا کر دیا کہ اب جدّہ سے مکّہ اور مکّہ سے مدینہ کی طرف موٹر چلتی ہے اُونٹ کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہی.اس پیشگوئی کا دوسرا پہلو یہ تھا کہ ایسے تیز رفتار جہاز پیدا ہو جائیں گے کہ جن کی وجہ سے ہر قسم کی سبزی ترکاری عرب میں پہنچنے لگ جائے گی چنانچہ پیشگوئی کا یہ حصہ بھی پورا ہوا.وہ قوم جس کی غذا ہی اونٹ کا دُودھ اور اُس کا
Page 310
گوشت تھا اب اس کو دنبے کا گوشت بھی میسر آرہا ہے.سبزیاں اور ترکاریاں بھی مل رہی ہیں اور اُسے اونٹ کا دودھ یا اُس کا گوشت کھانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی.اونٹ کا دودھ آخر ضرورت کے ماتحت ہی پیا جاتا تھا یہ تو نہیں کہ وہ کوئی مزیدار شے ہے مَیں نے خود اسے پی کر دیکھا ہے ایسا بدمزہ ہوتا ہے کہ اس کے پینے سے قے آتی ہے جس شخص کو کھانے کے لئے اَور کچھ نہ ملے وہ بے شک یہ دُودھ پی سکتا ہے مگر جسے اور چیزیں کھانے کے لئے مل جائیں وہ اُونٹنی کا دُودھ کیوں پئے گا.اسی طرح اونٹ کا گوشت بھی بڑا سخت ہوتا ہے اور گو عرب لوگ اُسے کھایا کرتے تھے مگر جب اُنہیں دُنبے کا گوشت کھانے کو مل جائے تو وہ اُونٹ کا گوشت کیوں کھائیں.اور جب سبزی ترکاری انہیں میسر آجائے تو وہ اونٹنی کے دودھ کی طرف کیوں رغبت کریں.یہی بات اس آیت میں بیان کی گئی تھی کہ نقل وحرکت کے سامان اس قدر کثرت سے نکل آئیں گے اور اتنی تیز رفتار سواریاں ایجاد ہو جائیں گی کہ ہر چیز عرب میں پہنچنے لگ جائے گی اس وجہ سے نہ اونٹ کی سواری کی کوئی اہمیت رہے گی اور نہ اونٹنی کے دُودھ اور اس کے بچہ کے گوشت کی قدر رہے گی.ہم دیکھتے ہیں عرب میں پان بھی پہنچ گیا ہے حالانکہ عرب کا پان سے کوئی تعلق نہیں لیکن جہازوں میں لد کر اب پان بھی عرب میں پہنچنے لگ گیا ہے اور ہندوستانی تو الگ رہے بعض عرب بھی شوق کے طور پر استعمال کرتے ہیں.اسی طرح اور کئی قسم کا سامان خوردونوش جو پہلے عرب کے واہمہ میں بھی نہیں آسکتا تھا اب وہاں آسانی سے پہنچ رہا ہے اور اس طرح اونٹ کے دودھ اور اس کے گوشت کی ضرورت بہت کم ہو گئی ہے اور روز بروز کم ہوتی جائے گی یہاں تک کہ اونٹ کی ضروت وہاں اسی طرح رہ جائے گی جس طرح دوسرے ملکوںمیں ہے اور پہلی سی بات اب بھی نہیں رہی آئندہ اور بھی تبدیل ہو جائے گی.وَ اِذَا الْوُحُوْشُ حُشِرَتْ۪ۙ۰۰۶ اور جب وحشی اکٹھے کئے جائیں گے.حَلّ لُغَات.اَلْوُحُوْشُ اَلْوُحُوْشُ حَیَوَانُ الْبَرِّ اَوْ مَا لَا بسْتَأنِسُ مِنْ دَوَابِّ الْبَرِّ جنگلی جانور یا وہ چوپایہ جو انسانوں سے مانوس نہ ہو وَحْشِیٌّ کہلاتا ہے اور وُحُوْشُ اس کی جمع ہے (اقرب) حُشِرَتْ حُشِرَتْ حَشَرَ سے مؤنث مجہول کا صیغہ ہے اور حَشَرَ النَّاسَ (حَشْرًا) کے معنے ہوتے ہیں جَمَعَھُمْ لوگوں کو جمع کیا.اور حَشَرَالسِّنَانَ کے معنے ہوتے ہیں دَقَّقَہٗ وَلَطَّفَہٗ اُس نے نیزے کی نوک کو خوب
Page 311
تیز کیا اور حَشَرَ فُلَانًا کے معنے ہوتے ہیں جَلَاہُ عَنْ وَطَنِہٖ اس کو اپنے وطن سے نکال دیا.اور حَشَرَ الْجَمْعَ کے معنے ہوتے ہیں اَخْرَجَہٗ مِنْ مَّکَانٍ اِلٰی اٰخَرَ.لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف منتقل کر دیا اور حُشِرَ مجہول کے صیغہ میں اس کے ایک زائد معنی بھی ہوتے ہیں چنانچہ کہتے ہیں حُشِرَتِ الْوُحُوْشُ اور مراد یہ ہوتی ہے کہ مَاتَتْ وَاُھْلِکَتْ یعنی وحشی مر گئے یا ان کو مار دیا گیا.(اقرب) پس وَاِذَا الْوُحُوْشُ حُشِرَتْ کے ایک معنے یہ ہوں گے کہ وحشیوں کو ہلا ک کر دیا جائے گا.تفسیر.یہ بھی ایک زبردست پیشگوئی ہے جو موجودہ زمانہ میں پوری ہوئی.اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ ایک زمانہ میں وحشی جانور جمع کئے جائیں گے.چنانچہ دیکھ لو آجکل چڑیا گھروں میں جس قدر وحشی جانور اکٹھے کئے گئے ہیں اس کی مثال پہلے زمانوںمیں کہاں ملتی ہے کوئی صوبہ اور کوئی ملک ایسا نہیں جہاں کوئی چڑیا گھر نہ ہو اور اس میں وحشی جانوروں کو اکٹھا نہ کیا گیا ہو پہلے زمانہ میں شائد ساری دنیا میں بھی کوئی ایک مقام ایسا نہیں مل سکتا تھاجہاں اس طرح جانور اکٹھے کئے گئے ہوں مگر اب کوئی ملک ایسا نہیں جس میں چڑیا گھر نہ ہوں.بلکہ کوئی صوبہ ایسا نہیں جس میں چڑیا گھر نہ ہو.اور پھر اس بارہ میں ملکوں اور صوبوں کی آپس میں رقابت پائی جاتی ہے اور ہر ملک یہ چاہتا ہے کہ وہ دوسروں سے زیادہ وحشی جانور اکٹھا کرے یہ تو چڑیا خانوں کا حال ہے جہاں زندہ وحشی جانور اکٹھے ہوتے ہیں عجائب گھروں میں مُردہ جانوروں کی کھالوں میں بھوسہ بھر بھر کر ان کو رکھا جاتا ہے تاکہ لوگ آئیں اُن کو دیکھیں اور اپنے معلومات میں اضافہ کریں.اسی طرح علم حیات کی تحقیقات کے لئے سائنٹفک ریسر چ انسٹیٹیوشن RESEARCH INSTITUTION میں مردہ جانوروں کے لاشے اور اُن کے ڈھانچے لا لا کر جمع کئے جاتے ہیں اور دیکھا جاتا ہے کہ یہ ڈھانچے کتنے سال کے ہیںیا کتنا زمانہ ان پر گزر چکا ہے یا اُن کی مختلف حالتوں کو دیکھنے اور دوسروں کو یاد کرانے کے لئے اُن ڈھانچوں پر غور کیا جاتا ہے غرض کیا چڑیا گھروں کے لحاظ سے اور کیا عجائب گھروں کے لحاظ سے اور کیا علم حیات کی تحقیق کے لحاظ سے اس پیشگوئی کی صداقت پوری طرح ثابت ہے اور جس طرح موجودہ زمانہ میں وحشی جانوروں کو زندہ یا مردہ اکٹھا کیا گیا ہے اس کی مثال پہلے کسی زمانہ میں نہیں ملتی.(۲) یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وُحُوْشُ سے مجازًا وحشی انسان مراد لئے جائیں.عربی زبان میں کثرت سے یہ لفظ اِن معنوں میں استعمال ہوتا ہے(المنجد).اُردو زبان میں بھی کہتے ہیں فلاں آدمی تو وحشی ہے اُس سے باتیں نہ کیجئے.یا فلاں لوگ تو وُحُوش ہیں.اسی لحاظ سے وَاِذَاالْوُحُوْشُ حُشِرَتْ کے یہ معنے ہوں گے کہ وحشی انسان یعنی جنگلی یا غیر تعلیم یافتہ اقوام جمع کی جائیں گی اور اُن کا تعلق بوجہ اشاعت تمدّن اور راستوں کے کھل جانے کے متمدن اقوام
Page 312
سے ہو جائے گا.پنجاب کے بار کے علاقہ میں چلے جائو تمہیں جگہ جگہ یہ سنائی دے گا کہ فلاں نئی آبادی ہے اور فلاں جانگلیوں کا گائوں ہے اور جانگلی کے معنے وحشی کے ہی ہیں.گویا وہ ادنیٰ یاوحشی اقوام جو پہلے الگ رہا کرتی تھیں اب متمدن لوگوں میں بالکل مل گئی ہیں.پہاڑی لوگوں کو بھی وحشی سمجھا جاتا تھا مگر اب ہر جگہ پہاڑوں پر سیر گاہیں بن گئی ہیںجن کی وجہ سے دنیا کے اکثر مالدار لوگ گرمی کا موسم پہاڑوں پر گزارتے ہیں اور اس طرح پہاڑی لوگوں کا تعلق بھی متمدن لوگوں سے ہو گیا ہے.مجھے یاد ہے ایک دفعہ ہم نور پورؔآرہے تھے جو پٹھانکوٹ سے پندرہ میل کے فاصلہ پر ہے.مولوی یار محمد صاحب مرحوم وکیل ہمارے ساتھ تھے ہم نے دیکھا کہ پگڈنڈی پر ایک عورت کھڑی ہے چونکہ ہم نے بھی اسی پگڈنڈی پر سے گزرنا تھا اِس لئے مولوی یار محمد صاحب نے اس عورت سے کہا کہ مائی ذرا ایک طرف ہو جائو.اُس نے یہ سُنتے ہی شور مچانا اور گالیاں دینا شروع کر دیا کہ میری ہتک کر دی گئی ہے.مولوی صاحب حیران تھے کہ میں نے اس کی کیا ہتک کی ہے اور ہم بھی حیرت زدہ تھے کہ یہ بات کیا ہوئی.مگر وہ برابر شور مچاتی اور گالیاں دیتی چلی گئی.آخر مولوی صاحب نے اس کی منتیں کیں کہ خدا کے لئے مجھے معاف کر دیا جائے اور کہا کہ ہمارے ہاں مائی کا لفظ عزت کےطور پر استعمال کیا جاتا ہے.اِسی لئے میں نے یہ لفظ استعمال کیا تھا میری غرض تمہاری ہتک کرنا نہیں تھی.مگر وہ کہتی جاتی تھی کہ تم نے تومجھے اپنے باپ کی بیوی بنا دیا ہے.اس وقت ہمیں معلوم ہوا کہ مائی کے معنے وہ عورت کیا سمجھتی تھی اور کیوں اُس نے گالیاں دیں اور شور مچایا.کچھ عرصہ گزرا کہ مجھے ڈلہوزی آتے ہوئے معلوم ہواکہ ہماری موٹر کا ڈرائیور نور پور کا ہے مَیں نے ڈرائیور کو راستہ میں یہ لطیفہ سُنا یا.وہ سُن کر کہنے لگا یہ بُہت پرانے زمانہ کی بات ہے اب عورتوں کو بے شک مائی کہہ کر دیکھ لیں انہیںبُرا محسوس نہیں ہو گا کیوں کہ اب پنجابی اُن سے ملنے لگ گئے ہیں اور وہ سب سمجھتی ہیں کہ مائی کے کیا معنے ہوتے ہیں مگر آج سے چالیس سال پہلے یہ کیفیت تھی کہ پندرہ بیس منٹ تک مولوی صاحب اس کی منّتیں کرتے چلے گئے اور وہ عورت کہتی جاتی تھی کہ تُو نے مجھے اپنے باپ کی بیوی بنا دیا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاِذَاالْوُحُوْشُ حُشِرَتْ ایک زمانہ میں ادنیٰ یا وحشی اقوام بھی متمدن لوگوںمیں ملا دی جائیں گی اور عالمگیر سیاسی نظام شروع ہو جائے گا جس کے دوسرے لفظوں میں یہ معنے ہوں گے کہ زمین کا چپّہ چپّہ آباد کر دیا جائے گا.ادنیٰ اقوام میں بھی بیداری پیدا ہو جائے گی اور اُن میں بھی تعلیم کا چرچا شروع ہو جائے گا چنانچہ ہم دیکھتے ہیں افریقہ کے باشندے پہلے ننگے پھرا کرتے تھے مگر اب وہی لوگ ولایت میں تعلیم حاصل کرنے کے لئے جاتے اور وہاں سے ڈاکٹر یا بیرسٹر وغیرہ بن کر واپس آتے ہیں.ہماری جماعت کے مبلغ مولوی عبدالرحیم صاحب نیّرؔافریقہ
Page 313
کے حبشیوں کی تصویریں دکھایا کرتے ہیں کہ جب تک احمدی مبلّغ وہاں نہیں پہنچے تھے وہ لوگ ننگے پھرا کرتے تھے مگر اب احمدی مبلّغین کے جانے کے بعد وہ لباس پہننے لگ گئے ہیں.غرض جس طرح اس زمانہ میں تمام وحشی اقوام کی تربیت ہو رہی ہے اس سے پہلے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی.انسان کسی ایک چیز کو اتفاق کہہ سکتا ہے مگر وہ ان سب علامتوں کو جو قرآن کریم نے ایک جا اور ایک زمانہ کے متعلق بیان فرمائی ہیں کس طرح اتفاقی قرار دے گا.(۳)یہ معنے بھی اس آیت کے ہو سکتے ہیں کہ جو اقوام نزول قرآن کے وقت وحشی سمجھی جاتی تھیں وہ اُبھار دی جائیں گی اور دنیا میں پھیل جائیں گی یعنی یورپ اور امریکہ کا غلبہ ہو گا.رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں یورپ بالکل وحشی تھا اور یورپ کے اکثر ممالک کے باشندے افریقہ کے حبشیوں کی طرح قریباً ننگے پھرا کرتے تھے.بلکہ آج سے پانچ چھ سو سال پہلے کی اگرتصویریں دیکھی جائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اُس وقت بھی وہ لوگ کھال کا لباس پہنا کرتے تھے.اُن کے گھٹنوں تک کھال ہوتی تھی.ہاتھ میں تیر کمان ہوتا تھا اور سر پر عجیب قسم کی ٹوپی ہوتی تھی.پس وَ اِذَا الْوُحُوْشُ حُشِرَتْ کے ایک یہ معنے بھی ہیں کہ جو قومیں نزول قرآن کے وقت وحشی سمجھی جاتی تھیں اُن کو اُبھار دیا جائے گا.وہ اجتماع اور طاقت اپنے اندر پیدا کر لیں گی اور دنیا میں پھیلا دی جائیں گی (۴)یا یہ کہ ایسی قوموں کی حکومت ہو جائے گی جو بے دین ہو جائیں گی کیونکہ انس وہ ہے جس میں دین ہو اور وحشی وہ ہے جس میں دین نہ ہو پس وَاِذَاالْوُحُوْشُ حُشِرَتْ کے ایک یہ معنے ہوں گے کہ بے دین حکومتیں قائم ہو جائیں گی جیسے رُوس میں یا اَور بعض دُوسرے ممالک میں ایسی حکومتیں قائم ہیں جن کو دین سے کوئی مس ہی نہیں.گویا دہریہ قوموں کے حاکم ہو جانے کے متعلق ان میں پیشگوئی پائی جاتی ہے.(۵)اس آیت کے یہ معنے بھی ہو سکتے ہیں کہ بد اخلاقی عام طور پر پھیل جائے گی اور دین دار لوگ دب جائیں گے.(۶)اس آیت کے ایک یہ معنے بھی ہو سکتے ہیں کہ وحشی اقوام کو اُن کے علاقوں سے نکال دیا جائے گا جیسا کہ افریقہ میں ہو رہا ہے.کینیا کالونی میں چلے جائو.یوگنڈا میں چلے جائو.ہر جگہ یہی نظارہ نظر آئے گا.انگریز وہاں گئے اور انہوں نے اصل باشندوں کو نوٹس دے دیا کہ یا تو اس زمین کو سنبھالو اور یا اس میں سے نکل جائو.وہاں ایک ایک شخص کی پچاس پچاس ساٹھ ساٹھ میل پرریاست ہوتی تھی مگر یوروپین قوموں نے جاتے ہی اُن سب کو اپنی زمینوںاور جائدادوں سے بے دخل کر دیا اور خود اُن پر قبضہ کر لیا.چنانچہ افریقہ میں بعض انگریزوں کے پاس ڈیڑھ ڈیڑھ لاکھ ایکڑ زمین ہے.اور گو انگریز بھی اس زمین کو بسا نہیں رہے مگر جب یہ وہاں گئے تو انہوں نے تمام لوگوں کو نوٹس دے دیا کہ اپنی اپنی زمین کو سنبھالو یا اسے چھوڑ دو.اب ایک شخص اتنی بڑی زمین کہاں سنبھال سکتا تھا نتیجہ یہ
Page 314
ہوا کہ انگریزوں نے اُن کو بے دخل کر دیا اور خود زمینوں پر قبضہ کر لیا.یہی حال امریکہ کا ہے وہاں ریڈ انڈینز RED INDIANSکی حکومت ہوا کرتی تھی اور شمالی اور جنوبی امریکہ سب اُن کے قبضہ میں تھا مگر انہوں نے سو سال میں اُن سب کو بے دخل کر دیا اور خود تمام علاقہ پر قبضہ کر لیا.(۷)حُشِرَتْ کے ایک معنے چونکہ اُھْلِکَتْ کے بھی ہیں اس لئے اس آیت کے ایک یہ معنے بھی ہو سکتے ہیں کہ اُنہیں قِسم قِسم کی تدابیر سے ہلاک کر دیا جائے گا.چنانچہ قدیم باشندوں کو یوروپینز نے قِسم قِسم کی اذّیتیں دے کر ہلاک کر دیا.اب ایک ریاست کے متعلق میں نے پڑھا ہے کہ اُس میں صرف تیرہ۱۳ قدیم باشندے باقی ہیں حالانکہ پہلے لاکھوں کی تعداد میں تھے.اسی طرح آسٹریلیا کے پُرانے باشندوں کا اب کہیں پتہ نہیں چلتا ان سب کو جو لاکھوں کی تعداد میں تھے یوروپین لوگوں نے قسم قسم کی تکالیف اور دُکھوں سے ایسا مٹایا کہ اب معلوم بھی نہیں ہوتا کہ وہ کہاں گئے.وَ اِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ۪ۙ۰۰۷ اور جب دریائوں (کے پانیوں) کو (نکال کر دوسری طرف) بہایا جائے گا.حَلّ لُغَات.بِحَارٌ بِحَارٌ جمع ہے بَحْرٌ کی اور اَلْبَحْرُ کے معنے ہیں خِلَافُ الْبَرِّ یعنی بحر کا لفظ خشکی کے مقابلہ میں استعمال ہوتا ہے.اسی طرح اس کے معنے ہیں.اَلْمَآءُ الْمِلْحُ.نمکین پانی والی جگہ یعنی سمندر.وَکُلُّ نَھْرٍ عَظِیْمٍ.ہر بڑا دریا.کُلُّ مُتَوَسِّعٍ فِیْ شَیْئٍ.ہر چیز میں وسعت رکھنے والا وجود.فَالرَّجُلُ الْمُتَوَسِّعُ فِیْ الْعِلْمِ بَحْرٌ وَالْفَرَسُ الْمُتَوَسِّعُ فِیْ جَرْ یِہٖ بَحْرٌ.ہر وہ آدمی جس کا علم وسیع ہو اسے بحر کہتے ہیں اور ہر وہ گھوڑا جو بہت تیز دوڑتا ہو اُسے بھی بحر کہتے ہیں (اقرب) غرض جس چیز میں بھی غیر معمولی وسعت پائی جاتی ہو عربی زبان میں اُسے بحر کہا جاتا ہے بُحُوْرٌ وَاَبْحُرٌ وَبِحَارٌ اس کی جمع ہیں.سُجِّرَتْ سُجِّرَتْ سَجَّرَ سے مجہول مؤنث کا صیغہ ہے اور سَجَّرَ الْمَآئُ کے معنے ہوتے ہیں فَـجَّرَہُ اس نے پانی کو پھاڑا اور سَـجَّر التَّنُورَ کے معنے ہوتے ہیں مَلَأَہٗ بِالْحَطَبِ لِیَحْمِیَہٗ.تنور کو لکڑیوںسے بھر دیا تا کہ اُس کو گرم کرے.وَفِیْ الْقُرْاٰنِ وَاِذَااالْبِحَارُ سُجِّرَتْ قِیْلَ اَیْ اُحْمِیَتْ بِتَفْجِیْرِ بَعْضِھَا اِلٰی بَعْضٍ حَتّٰی یَعُوْدَ بَحْرًا وَاحِدًا.لُغت میں جو لکھا ہے کہ قرآن میںجو آتا ہے اِذَاالْبِحَارُ سُجِّرَتْ.اس کے یہ معنے کئے جاتے ہیں کہ
Page 315
بعض دریائوں کو بعض میں پھاڑ کر ملا دینے سے پانی میں جوش پیدا کر دیا جائے گا یہاں تک کہ ایک بڑا دریا نظر آنے لگ جائے گا (اقرب) تفسیر.دریائوں کا پھاڑنا دو طرح ہو سکتا ہے.اوّلؔ اس طرح کہ اس کا پانی کسی اور طرف لے جایا جائے.دُوسرے اس طرح کہ اس میں کوئی اور پانی ملا دیا جائے.پس اس آیت کے معنے یہ ہوئے کہ یا تو دریا نہریں نکال نکال کر خشک کر دئے جائیں گے یا دریائوں میں اور پانی ملا کر اُن کو بڑھا دیا جائے گا.یہ دونوں نظّارے آج کل دنیا میں نظر آتے ہیں چنانچہ کئی دریا ایسے ہیں جن میں سے نہریں نکال نکال کر ان کو خشک کر دیا گیا ہے اور کئی دریا ایسے ہیں جن میں دوسرے دریائوں کا پانی ملا کر اُن کو وسیع کر دیا گیا ہے.ہمارے ملک میں دریائوں کو جہاز رانی کے قابل نہیں سمجھا گیا لیکن یورپ میں اس کا بڑا رواج ہے اور وہ دریائوں کو درست کر کے اندرون ملک میں بھی جہاز چلاتے ہیں تا کہ رسل و رسائل میں آسانی رہے.اب تک کے تجربہ سے یہی ثابت ہوا ہے کہ ریل نقل اسباب کے لحاظ سے مہنگی ہے لیکن جہاز سستا ہے اس وجہ سے یوروپین لوگ تجارت کے لئے جہازوں سے زیادہ کام لیتے ہیں اور جہاں دریا سمندر سے ملتے ہیں اس علاقہ کو صاف اور ہموار کر کے دریا کو جہاز رانی کے قابل بنا دیتے ہیں جس کی وجہ سے تیس تیس چالیس چالیس پچاس پچاس بلکہ بعض جگہ سَو سَو میل تک وہ اندرون ملک میں جہاز لے جاتے ہیں اور اس طرح اُن کو تجارت میں بہت آسانی رہتی ہے.ہمارے ملک میں اس کا رواج نہیں لیکن وہاں اس کا کثرت سے رواج ہے.اِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْمیں دریاؤں سے نہریں نکالے جانے کی پیشگوئی اور پھر یہ بھی ہو رہا ہے کہ دریائوں میں سے نہریں نکالی جاتی ہیں بلکہ بعض جگہ وسیع نہریں نکالنے کے لئے ایک دریا کا پانی دوسرے دریا کے پانی میں ملا دیتے ہیں اور اس طرح بحار کی تسبحیر عمل میں آرہی ہے.وَاِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْکے یہ معنے بھی ہو سکتے ہیں کہ عالم جاہل ہو جائیں گے اور ان کا علم مفقود ہو جائے گا کیونکہ بحر کے ایک معنے عالم کے بھی ہیں اور چونکہ بحر کے معنے اَلْمَاءُ الْمِلْحُ کے بھی ہیں یعنی صرف دریا مراد نہیں بلکہ اس کے معنے سمندر کے بھی ہیں اس لئے اس آیت کے یہ معنے بھی ہو سکتے ہیں کہ سمندر آپس میں ملا دئے جائیں گے جیسے نہر سویز کے ذریعہ سے قلزم اور روم کو یا نہر پانامہ کے ذریعہ سے دو ۲ امریکن سمندروں کو آپس میں ملا دیا گیا.
Page 316
وَ اِذَا النُّفُوْسُ زُوِّجَتْ۪ۙ۰۰۸ اور جب (مختلف) نفوس جمع کئے جائیں گے.تفسیر.اس آیت میں رسل ورسائل اور سفر کی آسانیوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ آخری زمانہ میںبعض ایسی چیزوں کی ایجاد عمل میں آجائے گی جن سے لوگ ایک دوسرے کے بالکل قریب ہو جائیں گے.چنانچہ پہلی چیز جو اس زمانہ میں قرآن کریم کی اس پیش کردہ صداقت کو ظاہر کر رہی ہے وہ ریل ہے.ریل کا ایک ڈبہ ہوتا ہے لیکن اگر غور کرو تواسی ایک ڈبہ میں کوئی چینی بیٹھا ہوتا ہے کوئی انگریز بیٹھا ہوتا ہے.کسی طرف بنگالی بیٹھا دکھائی دیتا ہے اور کسی طرف پٹھان بولتا نظر آتا ہے.اِسی طرح پنجابی بھی اسی ڈبہ میں موجود ہوتا ہے.غرض مختلف علاقوں کے رہنے والے اور مختلف زبانوں کے بولنے والے لوگ ریل کے ایک ڈبہ میں موجود ہوتے ہیں.پہلے زمانہ میں بڑی مشکل سے دوسرے علاقہ یا دوسرے ملک کے لوگ نظر آیا کرتے تھے مگر اب ذرائع رسل ورسائل اور آمدورفت میں اس قدر آسانی اور سہولت پیدا ہو گئی ہے کہ ہندوستا ن کے آدمی امریکہ میں نظر آجاتے ہیں اور امریکہ کے ہندوستان میں نظر آجاتے ہیں.پھر تارؔ.ریڈیو اور ڈاکؔ خانہ یہ تو ایسی چیزیں ہیں جنہوں نے وَ اِذَا النُّفُوْسُ زُوِّجَتْ کی پیشگوئی کو نہایت واضح طور پر پورا کر دیا ہے.ہم گھر میں آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں.اور ریڈیو پر کبھی چینیوں کی تقریریں سن رہے ہوتے ہیں کبھی جاپانیوں کے لیکچر سُن رہے ہوتے ہیں.کبھی جرمنوں اور کبھی انگریزوں کی باتیں ہمارے کانوں تک پہنچ رہی ہوتی ہیں گویا دوسرے الفاظ میں ہم اور ایک چینی ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں یا ہم اور ایک جاپانی ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہوتےہیں یا ہم اور ایک انگریز ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں یا ہم اور ایک جرمن ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں.وَ اِذَا النُّفُوْسُ زُوِّجَتْ میں اس طرف بھی اشارہ کیا گیا تھا کہ اس زمانہ میں ایک قسم کے علوم پھیل جائیں گے چنانچہ دنیا میں مغربی علوم کا اب اس قدر غلبہ ہو گیا ہے کہ نفوس انسانی کا آپس میں جوڑ اور اتحاد پیدا ہونا بالکل آسان ہو گیا ہے.اس زمانہ میں یہ علوم اتنے غالب آ گئے ہیں کہ ساری دنیا پر چھا گئے ہیں.بالخصوص یوروپین فلسفہ نے انسانی دماغ کو ایک خاص رنگ میں ڈھال دیا ہے اب اگر ایک چینی سو چتا ہے تو مغربی رنگ میں سوچتا ہے جاپانی سوچتا ہے تو مغربی رنگ میں سوچتا ہے عرب سوچتا ہے تو مغربی رنگ میں اور پٹھان سوچتا ہے تو وہ بھی مغربی رنگ میں.حالانکہ جُدا جُدا قومیں ہیں.جُدا جُدا زبانیں ہیں مگر مغربی فلسفہ اور مغربی تہذیب سب پر چھا گئی ہے.اور مختلف
Page 317
وَ اِذَا النُّفُوْسُ زُوِّجَتْ میں اس طرف بھی اشارہ کیا گیا تھا کہ اس زمانہ میں ایک قسم کے علوم پھیل جائیں گے چنانچہ دنیا میں مغربی علوم کا اب اس قدر غلبہ ہو گیا ہے کہ نفوس انسانی کا آپس میں جوڑ اور اتحاد پیدا ہونا بالکل آسان ہو گیا ہے.اس زمانہ میں یہ علوم اتنے غالب آ گئے ہیں کہ ساری دنیا پر چھا گئے ہیں.بالخصوص یوروپین فلسفہ نے انسانی دماغ کو ایک خاص رنگ میں ڈھال دیا ہے اب اگر ایک چینی سو چتا ہے تو مغربی رنگ میں سوچتا ہے جاپانی سوچتا ہے تو مغربی رنگ میں سوچتا ہے عرب سوچتا ہے تو مغربی رنگ میں اور پٹھان سوچتا ہے تو وہ بھی مغربی رنگ میں.حالانکہ جُدا جُدا قومیں ہیں.جُدا جُدا زبانیں ہیں مگر مغربی فلسفہ اور مغربی تہذیب سب پر چھا گئی ہے.اور مختلف اقوام کے افراد علمی طور پر آپس میں ملا دئے گئے ہیں.اسی طرح اس کے یہ معنے بھی ہیں کہ مختلف اقوام کے افراد کا آپس میں شادی بیاہ کرنے کا رواج ہو جائے گا.چنانچہ حبشی عورتیں انگریزوں اور فرانسیسیوں کے ساتھ بیاہی جاتی ہیں اور انگریز عورتیں دوسری اقوام کے مردوں سے شا دی کر لیتی ہیں.فرانس میں چلے جاؤ تو تمہیں نظر آئے گا کہ ایک فرانسیسی اپنی حبشی بیوی کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے جا رہا ہے اُسے یہ احساس تک نہیں ہوتا کہ میں فرانسیسی ہوں اور یہ حبشی ہے اس طرح انٹر میرج بلزINTER MARRIAGE BILLSپاس ہونے شروع ہو گئے ہیں تاکہ غیر مذاہب والوں کے ساتھ شادی بیاہ میں کوئی روک نہ ہو پہلے اس قسم کی شادیاں لوگ بہت رُک رُک کر کرتے تھے مگر اب زور دے کر انٹر میرج بلز پاس کرائے جاتے ہیں تا کہ اس قسم کی شادیوں میں کوئی روک پیدا نہ ہو سکے.لاہور میں اُمّ طاہرؓ کی بیماری کے سلسلہ میں جب مَیں مقیم تھا تو ایک بہت بڑے لیڈر مجھ سے ملنے کے لئے آئے.اُن کی بیوی بھی ان کے ساتھ تھیں باتوں باتوں میں ان کی بیوی نے جو مسلمان ما ں باپ کے گھر میں پیدا ہوئی تھی بتایا کہ ہم تین بہنیں ہیں جن میں سے دو ہندوئوں میں بیاہی ہوئی ہیں اور ایک کی مسلمان کے ساتھ شادی ہو چکی ہے.پشاور میں ایک دفعہ اسی بات پر بہت شور اٹھا تھا کیونکہ ڈاکٹر خان کی بیٹی نے ایک سکھ ہوا باز سے شادی کر لی تھی.غرض مختلف قوموں میں اس قسم کی شادیوں کا رواج بہت ترقی کر چکا ہے جو قرآن کریم کی پیشگوئی وَ اِذَا النُّفُوْسُ زُوِّجَتْ کی صداقت کا ثبوت ہے.اسی طرح اس کے ایک یہ بھی معنے ہیں کہ مختلف قسم کے نفوس مل جائیں گے اور وہ اپنی اپنی الگ سوسائٹیاں بنائیں گے چنانچہ دیکھ لو کہیںلیبر پارٹی بنی ہوئی ہے.کہیں فاشسٹ پارٹی بنی ہوئی ہے.کہیں کمیونسٹ پارٹی بنی ہوئی ہے.اور کہیں سوشلسٹ پارٹی بنی ہوئی ہے.چند ہم خیال لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور پھر وہ اپنی اپنی پارٹیاں بنا لیتے ہیں.مزدور اپنے حق کے لئے لڑتا ہے.صنّاع اپنے حقوق کے لئے جدوجہد کرتا ہے اور مدرس اور تاجر اپنے اپنے رنگ میں کوشش کرتا ہے غرض قومی سوسائٹیاں بڑی کثرت سے بن گئی ہیں اور ہر سوسائٹی کوشش کرتی ہے کہ اس کے ہم پیشہ افراد کے حقوق پامال نہ ہوں.اور ترقی کی دوڑ میں وہ دوسروں سے پیچھے نہ رہے.یہ تمام علامات ایسی ہیں جو اس زمانہ کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں اور اِسی زمانہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو پورا کیا ہے.دنیا کی تاریخ میں اور کوئی زمانہ ایسا پیش نہیں کیا جا سکتا جس میں یہ علامات پوری ہوئی ہوں.ہر شخص جس کے سامنے ان علامات کو رکھا جائے وہ یہی کہے گا کہ ان میں موجودہ زمانہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اَور کسی زمانہ کی طرف اشارہ نہیں کیا گیا.روایات میں آتا ہے کہ حضرت عمررضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ خطبہ پڑھا اور کہا وَاِذَا لنُّفُوْسُ
Page 318
زُوِّجَتْ پھر آپ نے فرمایا تَزَوَّجُھَا اَنْ تُؤَلِّفَ کُلُّ شِیْعَۃٍ اِلٰی شِیْعَتِھِمْ (رواہ بن ابی حاتم عن نعمان بن بشیر بحوالہ ابن کثیر) یعنی اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایک خیال یا پیشہ کے لوگ آپس میں سوسائٹیاں بنا لیں گے.سو جیسا کہ موجودہ زمانہ کے حالات سے ظاہر ہے یہ پیشگوئی بڑی وضاحت سے پوری ہو چکی ہے.وَ اِذَا الْمَوْءٗدَةُ سُىِٕلَتْ۪ۙ۰۰۹ اور جب زندہ گاڑی جانے والی (لڑکی) کے بارے میں سوال کیا جائے گا بِاَيِّ ذَنْۢبٍ قُتِلَتْۚ۰۰۱۰ (کہ آخر) کس گناہ کے بدلہ میں اُس کو قتل کیا گیا (تھا).حل لغات.مَوْءٗ دَۃٌ مَوْءٗ دَۃٌ وَاَدَ سے نکلا ہے اور وَاَدَبِنْتَہٗ (یَئِدُھَا) وَاْدًا کے معنے ہوتے ہیں دَفَنَھَا فِی الْقَبْرِ وَھِیَ حَیَّۃٌ اُس نے اپنی لڑکی کو زندہ ہی قبر میں دفن کر دیا.وَعِبَارَۃُ الْاَسَاسِ اَثْقَلَھَا بِالتُّرَابِ (اقرب) اور زمخشری اپنی کتاب اساس میںلکھتے ہیں کہ اِس کےمعنے اَثْقَلَھَا باالتُّرَابِ کے ہوتے ہیں یعنی اُس پر مٹی کا بوجھ ڈال دیا.پھر لکھا ہے فَھِیَ وَئِیْدَۃٌ وَمَوْءٗ دَۃٌ یعنی مَوْءٗ دَۃٌ کو وَئِیْدٌ اور وَئِیْدَۃٌ بھی کہتے ہیں (اقرب) تفسیر.وَ اِذَا الْمَوْءٗدَةُ سُىِٕلَتْکے معنے پہلے مفسرین کے نزدیک اور ان کے معنی کی تغلیط وَ اِذَا الْمَوْءٗدَةُ سُىِٕلَتْ کے معنے یہ ہیں کہ زمین میں زندہ دفن کی جانے والی لڑکی کے بارہ میں سوال کیا جائے گا.لیکن مفسّرین اس کے یہ معنے کرتے ہیں کہ مَوْئٗ دَةُ سے سوال کیا جائے گا.لیکن میرے نزدیک یہ معنے قرآن کریم کے محاورہ کے لحاظ سے درست نہیں ہیں.مفسّرین نے اس کی یہ توجیہ کی ہے کہ موئودہ سے پوچھنے میں زجر زیادہ ہے کیونکہ اُس سے گواہی طلب کی جا رہی ہو گی(الکشاف زیر آیت ھذا) لیکن میںسمجھتا ہوں یہ معنے قرآن کریم کے اسلوبِ بیان اور متعارف طریقِ عمل کے خلاف ہیں.قرآن کریم سے صاف پتہ لگتا ہے کہ سوال مجرم سے ہی کیا جاتا ہے نہ کہ اُس سے جس پر ظلم کیا گیا ہو چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَایُسْئَلُ عَمَّا یَفْعَلُ وَھُمْ یُسْئَلُوْنَ (الانبیاء:۲۴) یعنی جو کچھ اللہ تعالیٰ کرتا ہے اُس کے متعلق اُس سے نہ پوچھا جائے گا ہاں یہ لوگ جو کچھ عمل کرتے ہیں اُس کے متعلق اُن سے سوال کیا جائے گا.اسی طرح پھر فرماتا ہے لِیَسْئَلَ الصّٰدِقِیْنَ عَنْ صِدْقِھِمْ (الاحزاب:۹)یعنی تاکہ اللہ تعالیٰ سچ بولنے والوں سے ان کی سچائی کا سوال کرے سورۂ عنکبوت میں فرماتا ہے
Page 319
تفسیر.وَ اِذَا الْمَوْءٗدَةُ سُىِٕلَتْکے معنے پہلے مفسرین کے نزدیک اور ان کے معنی کی تغلیط وَ اِذَا الْمَوْءٗدَةُ سُىِٕلَتْ کے معنے یہ ہیں کہ زمین میں زندہ دفن کی جانے والی لڑکی کے بارہ میں سوال کیا جائے گا.لیکن مفسّرین اس کے یہ معنے کرتے ہیں کہ مَوْئٗ دَةُ سے سوال کیا جائے گا.لیکن میرے نزدیک یہ معنے قرآن کریم کے محاورہ کے لحاظ سے درست نہیں ہیں.مفسّرین نے اس کی یہ توجیہ کی ہے کہ موئودہ سے پوچھنے میں زجر زیادہ ہے کیونکہ اُس سے گواہی طلب کی جا رہی ہو گی(الکشاف زیر آیت ھذا) لیکن میںسمجھتا ہوں یہ معنے قرآن کریم کے اسلوبِ بیان اور متعارف طریقِ عمل کے خلاف ہیں.قرآن کریم سے صاف پتہ لگتا ہے کہ سوال مجرم سے ہی کیا جاتا ہے نہ کہ اُس سے جس پر ظلم کیا گیا ہو چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَایُسْئَلُ عَمَّا یَفْعَلُ وَھُمْ یُسْئَلُوْنَ (الانبیاء:۲۴) یعنی جو کچھ اللہ تعالیٰ کرتا ہے اُس کے متعلق اُس سے نہ پوچھا جائے گا ہاں یہ لوگ جو کچھ عمل کرتے ہیں اُس کے متعلق اُن سے سوال کیا جائے گا.اسی طرح پھر فرماتا ہے لِیَسْئَلَ الصّٰدِقِیْنَ عَنْ صِدْقِھِمْ (الاحزاب:۹)یعنی تاکہ اللہ تعالیٰ سچ بولنے والوں سے ان کی سچائی کا سوال کرے سورۂ عنکبوت میں فرماتا ہے وَلَیُسْئَلُنَّ یَوْمَ الْقِیَامَۃِ عَمَّا کَانُوْا یَفْتَرُوْنَ (العنکبوت:۱۴)اور ضرور اِن لوگوں سے قیامت کے دن اس کا سوال کیا جائے گا جو یہ افتراء کرتے تھے.پھر فرماتا ہےوَ جَعَلُوا الْمَلٰٓىِٕكَةَ الَّذِيْنَ هُمْ عِبٰدُ الرَّحْمٰنِ اِنَاثًا١ؕ اَشَهِدُوْا خَلْقَهُمْ١ؕ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَ يُسْـَٔلُوْنَ(الزخرف:۲۰)یعنی اِن لوگوں نے فرشتوں کو جو رحمٰن کے بندے ہیں لڑکی بنا دیا.کیا انہوں نے اُن کی پیدائش کو دیکھا ہے.عنقریب ان کی گواہی لکھ لی جائے گی اور اُن سے اس کا سوال کیا جائے گا.اِن آیات سے ہم کو پتہ لگتا ہے کہ جہاں جہاں سوال کا ذکر آتا ہے وہاں مجرم سے ہی پوچھے جانے کا ذکر آتا ہے نہ کہ غیر مجرم سے.البتہ ایک مقام ایسا ہے جہاں یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ وہاں ایک غیر مجرم سے سوال کیا گیا ہے اور وہ مقام وہ ہے جہاں حضرت میسح ناصری ؑ سے سوال کیا گیا ہے.اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَ اِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَاَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوْنِيْ وَ اُمِّيَ اِلٰهَيْنِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ١ؕ قَالَ سُبْحٰنَكَ مَا يَكُوْنُ لِيْۤ اَنْ اَقُوْلَ مَا لَيْسَ لِيْ١ۗ بِحَقٍّ١ؐؕ اِنْ كُنْتُ قُلْتُهٗ فَقَدْ عَلِمْتَهٗ١ؕ تَعْلَمُ مَا فِيْ نَفْسِيْ وَ لَاۤ اَعْلَمُ مَا فِيْ نَفْسِكَ١ؕ اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ ( المائدۃ:۱۱۷)یعنی جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ بن مریم کیاتم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو؟ عیسیٰ کہیں گے کہ میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں اور تُو پاک ہے.مجھے یہ ہر گز سزاوار نہیں کہ مَیں وہ بات کہوں جس کا مجھے حق نہیں.اگر میں نے یہ کہا ہو گا تو بے شک تُو اسے جانتا ہو گا کیوں کہ تُو جانتا ہے جو کچھ میرے دل میں ہے اور میں نہیں جانتا جو کچھ تیرے علم میں ہے اس لئے کہ بے شک چھپی ہوئی باتوں کا جاننے والا تُو ہی ہے.لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ نصاریٰ کہتے تھے کہ حضرت مسیح ؑ نے ہم کو یہ تعلیم دی ہے اس لئے نصاریٰ کو جھوٹا کرنے کے لئے حضرت مسیح ؑ سے اس سوال کا پوچھا جانا ضروری تھا.لیکن یہاں یہ بات کس طرح چسپاں ہو سکتی ہے کہ موئودہ کہتی تھی کہ مجھے بے شک زمین میں دفن کر دو.اگر کفار کا دعویٰ ہوتا کہ موئودہ نے ہمیں کہا ہے کہ مجھے زندہ گاڑ دیا جائے تو اس صورت میں بے شک اس سے سوال ہو سکتا تھا اور گاڑنے والا کہہ سکتا تھاکہ آپ مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں خود اُس سے پوچھ کر دیکھ لیجئے اس نے خود کہا تھا کہ مجھے زندہ گاڑ دیا جائے.لیکن جب موئودہ کی نسبت ایسی کوئی بات نہیں کہی جاتی تو موئودہ سے سوال کرنے کے بھی کوئی معنے نہیں ہو سکتے.میرے نزدیک اس جگہ حذف ہےاور وَ اِذَا الْمَوْءٗدَةُ سُىِٕلَتْ درحقیقت وَاِذَا الْمَوْئٗ دَۃُ سُئِلَتْ عَنْھَا ہے یعنی جب کہ موئودہ کے بارہ میں سوال کیا جائے گا اور چونکہ موئودہ کسی حق سے نہیں گاڑی جاتی اس لئے جب اس کے بارہ میں مجرم سے سوال کیا جائے گا تو مجرم پھنس جائے گا.یوں تو مومن سے بھی حساب لیا جائے گا اور کافر سے بھی حساب لیا جائے گا مگر مومن اور کافر کے حساب میں فرق یہ ہے کہ مومن سے آسان حساب لیا جائے گا جیسا کہ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَّسِيْرًا (الانشقاق:۹) سے ظاہر ہے ایک دو سرسری باتیں پوچھ کر اُسے چھوڑ دیا جائے گا.لیکن جب کافر سے حساب لیا جائے گا تو بڑی سختی سے لیا جائے گا.احادیث میںبھی آتا ہے کہ رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَنْ نُّوْقِشَ الْحِسَابَ عُذِّبَ (بخاری کتاب الرقاق باب مَن نوقش الحساب عُذِّبَ) یعنی جس سے سختی سے حساب لیا گیا وہ ضرور عذاب میں مبتلا ہو گا.درحقیقت مجرم سے جب کوئی سوال کیا جاتا ہے اور اس میں سختی سے کام لیا جاتا ہے تو اس سے غرض یہ ہوتی ہے کہ حساب لے کر اُسے سزا دی جائے لیکن مومن کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات سے حصہ دینا ہے اس لئے اُس کے اچھے اچھے اعمال نکال کر اُس کے سامنے رکھے جائیں گے اور پوچھا جائے گا کہ بتائو.کیا تم نے یہ کام کئے تھے اور جب وہ اقرار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اُسے جنت میں داخل کردے گا.گویا کافر کے حساب کی غرض اُسے ذلیل کرنا ہے لیکن مومن کے حساب کی غرض یہ ہو گی کہ اس کے اچھے اچھے کام لوگوں پر ظاہر کئے جائیں اور انہیں پتہ لگے کہ اُس نے کیسے کیسے نیک اعمال کئے ہیں.اسی طرح فرماتا ہے اُس دن موئودہ کے بارہ میں مجرموں سے سختی سے سوال کیا جائے گا اور اُن سے پوچھا جائے گا کہ بتائو تم نے جو ان کو زندہ درگور کیا تھا تو اُن کا کیا قصور تھا؟
Page 320
يُحَاسَبُ حِسَابًا يَّسِيْرًا (الانشقاق:۹) سے ظاہر ہے ایک دو سرسری باتیں پوچھ کر اُسے چھوڑ دیا جائے گا.لیکن جب کافر سے حساب لیا جائے گا تو بڑی سختی سے لیا جائے گا.احادیث میںبھی آتا ہے کہ رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَنْ نُّوْقِشَ الْحِسَابَ عُذِّبَ (بخاری کتاب الرقاق باب مَن نوقش الحساب عُذِّبَ) یعنی جس سے سختی سے حساب لیا گیا وہ ضرور عذاب میں مبتلا ہو گا.درحقیقت مجرم سے جب کوئی سوال کیا جاتا ہے اور اس میں سختی سے کام لیا جاتا ہے تو اس سے غرض یہ ہوتی ہے کہ حساب لے کر اُسے سزا دی جائے لیکن مومن کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات سے حصہ دینا ہے اس لئے اُس کے اچھے اچھے اعمال نکال کر اُس کے سامنے رکھے جائیں گے اور پوچھا جائے گا کہ بتائو.کیا تم نے یہ کام کئے تھے اور جب وہ اقرار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اُسے جنت میں داخل کردے گا.گویا کافر کے حساب کی غرض اُسے ذلیل کرنا ہے لیکن مومن کے حساب کی غرض یہ ہو گی کہ اس کے اچھے اچھے کام لوگوں پر ظاہر کئے جائیں اور انہیں پتہ لگے کہ اُس نے کیسے کیسے نیک اعمال کئے ہیں.اسی طرح فرماتا ہے اُس دن موئودہ کے بارہ میں مجرموں سے سختی سے سوال کیا جائے گا اور اُن سے پوچھا جائے گا کہ بتائو تم نے جو ان کو زندہ درگور کیا تھا تو اُن کا کیا قصور تھا؟ یہاں مفسّرین نے ایک بحث کی ہے جو گو ایک ضمنی مضمون کے طور پر نکلتی ہے لیکن وہ ایک نہایت ہی اہم مضمون ہے.اگرچہ جہاں تک عقائد کا سوال ہے وہ مضمون غیر اہم ہے اور اس لحاظ سے بھی اس کا چندہ فائدہ نہیں کہ اگلے جہان کے متعلق اُس میں بحث کی گئی ہے جس کا اس جہان میں کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہو سکتا.لیکن بہرحال چونکہ وہ ایک علمی مضمون ہے اس لئے میں اُس مضمون کو اس جگہ بیان کر دینا چاہتا ہوں.وَ اِذَا الْمَوْءٗدَةُ سے زمخشری کا یہ خیال کہ مشرکین کے بچے نجات پا جائیں گے مفسّرین لکھتے ہیں وَ اِذَا الْمَوْءٗدَةُ سُىِٕلَتْ سے زمخشری نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ مشرکوں کے بچے نجات پا جائیں گے.انہوں نے یہ استدلال اس رنگ میں کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں اس آیت میں یہ ذکر آتا ہے کہ مَوْءٗ دَۃُ سے یا مَوْءٗ دَۃُ کے بارے میں (ان دونوں میں سے کوئی سمجھ لو) یہ سوال کیا جائے گا بِاَيِّ ذَنْۢبٍ قُتِلَتْ کہ وہ کس گناہ کے بدلہ میں ماری گئی ہے (تفسیر کشاف زیر آیت ھذا).وہ کہتے ہیں اس آیت سے یہ پتہ لگتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے اُسے صَاحِبَۃُ الذَّنْب قرار نہیں دیا اگر وہ صَاحِبَۃُ الذَّنْب ہوتی تو اس کے متعلق یہ نہ کہا جاتا کہ بِاَيِّ ذَنْۢبٍ قُتِلَتْ اسی بحث میں دوسرے مفسّرین بھی پڑ گئے ہیںکہ زمخشری نے اس آیت سے جو نتیجہ نکالا ہے وہ صحیح ہے یا نہیں یا یہ مسئلہ اپنی ذات میں غلط ہے یا درست.جہاں تک اس آیت سے یہ نتیجہ نکالا گیا ہے کہ مجرموں کے بچے بَری ہیں اور وہ جنت میں جائیں گے
Page 321
اس میں زمخشری نے حضرت ابن عباسؓ کی اتباع کی ہے.حدیثوں میں آتا ہے کہ حضرت ابن عباسؓ سے سوال کیا گیا کہ بعض لوگ کہتے ہیں مشرکین کے بچے جہنمی ہوں گے.آپ نے فرمایا وہ جھوٹ بولتے ہیں قرآن کریم میں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَ اِذَا الْمَوْءٗدَةُ سُىِٕلَتْ پس جو شخص یہ کہتا ہے کہ کفار کے بچے جہنم میں جائیں گے وہ جھوٹ بولتا ہے (مگر صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ یہ اثر ضعیف ہے) اس میں حضر ت ابن عباس نے بھی اسی آیت سے استدلال کیا ہے مگر حضرت ابن عباسؓ نے وجہ استدلال نہیں بتائی صرف آیت بتا دی ہے لیکن زمخشری نے وجہِ استدلال بِاَيِّ ذَنْۢبٍ قُتِلَتْ کو قرار دیا ہے.اور اس سے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ کفار کے بچوں کو بری قرار دیا گیا ہے.زمخشری کے استدلال کی تردید مگر جہاں تک زمخشری کا استدلال اس آیت سے ہے وہ بالکل غلط ہے بِاَيِّ ذَنْۢبٍ قُتِلَتْ سے یہ نتیجہ ہر گز نہیں نکل سکتا کہ کفّار کے بچے جنت میں جائیں گے.اس لئے کہ کسی خاص شخص کا اگر کسی خاص پہلو میں مجرم ہونا ثابت نہ ہو تو یہ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا کہ وہ کسی لحاظ سے بھی مجرم نہیں.ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور لحاظ سے مجرم اور گنہگار ہو.بے شک جہاں تک بچے کا سوال ہے اور جہاں تک صرف اس جرم کا تعلق ہے یہ استدلال درست ہے لیکن عام طور پر نہیں کیوں کہ ایک جرم کےنہ ہونے سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ دوسرا کوئی جُرم بھی نہیں ہے.پس میں زمخشری کے اس نتیجہ سے اختلاف کرتے ہوئے اس سلسلۂ مضامین کی بعض اور کڑیاں بیان کرتا ہوں.آخر میں مَیں اس بارہ میں اپنے نقطۂ نگاہ کی بھی وضاحت کر دوں گا.زمخشری کے علاوہ حضرت ابن عباسؓ کا بھی ایک قول پیش کیا جاتا ہے مگر چونکہ انہوں نے وجہ استدلال بیان نہیں کی اس لئے ہمیں دوسری نگاہ سے اس مسئلہ پر غور کرنا چاہیے زمخشری نے کہا ہے کہ بِاَيِّ ذَنْۢبٍ قُتِلَتْ سے یہ نتیجہ نکلتا ہے.مگر جیسا کہ میںبتا چکا ہوں اس آیت سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا.کیوں کہ کسی ایک جرم میں کسی کا مجرم نہ ہونا یہ ثابت نہیں کرتا کہ وہ کسی لحاظ سے بھی مجرم نہیں ہے.ہو سکتاہے کہ وہ بعض اور وجوہ سے مجرم ہو.لیکن ایک بات ضرور ہے جو زمخشری کے حق میں ہے اور وہ یہ کہ یہ سوال ایک بچہ کے متعلق ہے اور جب بچہ کے متعلق سوال ہے تو چونکہ بِاَيِّ ذَنْۢبٍ قُتِلَتْ ایک نابالغ بچہ کے متعلق ہے اور وہ شریعت کا مکلّف نہیں اس لئے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر اُس نے یہ گناہ نہیں کیا تو کوئی اور گناہ کیا ہو گا.گو عام طور پر اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ جب اُس نے کوئی ایسا جرم نہیں کیا جو اُسے اس سزا کا مستحق بناتا تو معلوم ہوا وہ بالکل بری ہے درست نہیں.لیکن بہرحال جب یہ سوال ایسے بچہ کے متعلق ہو گا جو بالغ نہیں تو بِاَيِّ ذَنْۢبٍ قُتِلَتْ میں مَوءٗدَۃُ کے گناہ کا ذکر نہیں سمجھا جائے گا بلکہ اُسے مارنے والے کے گناہ کا اس میں ذکر سمجھا جائے گا کہ تو نے یہ فعل کس بناء پر کیا تھا.
Page 322
مشرکین کے بچوں کے جنت میں جانے کے بارہ میں علماء کا اختلاف مشرکین کی اولاد کے بارہ میں علماء میں سخت اختلاف ہے کہ وہ جنّتی ہے یا نہیں.اس بارہ میں احادیث بھی اور آثار بھی بعض لوگوں نے نقل کئے ہیں جو یہ ہیں.امام احمد بن حنبل نے سلمۃ بن یزید الجعفی سے روایت کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَلْوَائِدَۃُ وَالْمَوْءٗدَۃُ فِی النَّارِ اِلَّا اَنْ تُدْرِکَ الْوَائِدَۃُ الْاِسْلَامَ فَیَعْفُوَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْھَا (بحوالہ روح المعانی و ابن کثیر) کہ زندہ گاڑنے والی اور زندہ گاڑی ہوئی دونوں جہنمی ہیں سوائے اس کے کہ جو گاڑنے والی زندہ رہ جائے وہ اسلام کا زمانہ پا لے تو اسلام قبول کرنے سے اس کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا.نسائی نے بھی یہ حدیث بیان کی ہے مگر نسائی کے راوی دائود بن ہندبہ ہیں.اور ابن ابی حاتم نے بھی ابن مسعود سے یہ روایت کی ہے کہ اَلْوَائِدَۃُ وَالْمَوْءدَۃُ فِیْ النَّارِ (ابن کثیر) یعنی زندہ گاڑنے والی اور زندہ گاڑی ہوئی دونوں جہنمی ہیں.اسی طرح ابو دائود اور نسائی حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَلَّ اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَسَلَّمَ عَنْ اَوْلَادِ الْمُشْرِکِیْنَ.فَقَالَ ’’ اَللّٰہُ تَعَالیٰ.اِذْخَلَقَھُمْ.اَعْلَمُ بِمَا کَانُوْا عَامِلِیْنَ‘‘ یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین کی اولاد کے بارہ میں سوال کیا گیا.آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب اُن کو پیدا کیا تھا تو وہ خوب جانتا تھا کہ وہ کیا کرنے والے ہیں.اس سے بھی وہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دوزخیوں کے گھر میں پیدا کیا تھا اس لئے وہ جہنم میں داخل کئے جائیں گے.ان معنوں کی تائید میں وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہاکی ایک روایت بھی نقل کرتے ہیں جو ابو دائود میں آتی ہے حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں قُلْتُ یَارَسُوْلَ اللّٰہِ ذَرَارِی الْمُؤْمِنِیْنَ میں نے کہا یا رسول اللہ! مومنوں کی اولاد کے متعلق کیا فتویٰ ہے؟ فَقَالَ مَن اٰبَآئِ ھِمْ.آپ نے فرمایا وہ اپنے آباء کے ساتھ ہیں قُلْتُ بِلاَعَـمَلٍ میں نے کہا یا رسول اللہ! کیا بغیر عمل کے؟ قَالَ.اَللّٰہُ تَعَالٰی اَعْلَمُ بِمَاکَانُوْا عَامِلِیْنَ.آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ وہ کرنے والے تھے.قُلْتُ یَارَسُوْلَ اللّٰہِ فَذَرَارِی الْمُشْرِکِیْنَ میں نے کہا یا رسول اللہ! مشرکین کی اولاد کے متعلق کیا حکم ہے؟ فَقَالَ مَع اٰبَآءِ ھِمْ.آپ نے فرمایا وہ اپنے آباء کے ساتھ ہیں قُلْتُ بِلَا عَمَلٍ میں نے کہا یا رسول اللہ کیا بغیر عمل کے؟ قَالَ.اَللّٰہُ تَعَالٰی اَعْلَمُ بِمَا کَانُوْا عَامِلِیْنَ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اُس کو بہتر جانتا ہے جو کچھ وہ کرنے والے تھے(سنن ابو داؤد کتاب السنة باب ما فی ذراری المشرکین) اس حدیث کو پہلی حدیث سے ملا کر وہ یہ استدلال کرتے ہیں کہ چونکہ اولاد مشرکین نے آئندہ مشرک ہی ہونا تھا اس لئے ضروری ہے کہ ان کو دوزخ میں داخل کیا جائے اس کے علاوہ مسند احمد بن حنبل میں حضرت خدیجہؓ کی طرف منسوب کر کے ایک روایت آتی ہے کہ اُنہوں نے رسول کریم صلے اللہ
Page 323
علیہ وسلم سے اپنے دو بچوں کے متعلق پوچھا جو جاہلیت کے زمانہ میں فوت ہوئے تھے کہ اُن کا کیا حال ہے؟ آپ نے فرمایا ھُمَا فِی النَّارِ وہ دونوں دوزخ میںہیں.(مسند احمد بن حنبل مسند حضرت عبداللہ بن مسعودؓ) یہ وہ احادیث اور آثار ہیں جن سے مشرکوں کے بچوں کے دوزخ میں جانے کے متعلق استدلال کیا جاتا ہے.امام نووی شرح صحیح مسلم میں فرماتے ہیں کہ تمام علماء جن کی رائے وقعت رکھتی ہے اس امر پر متفق ہیں کہ مسلمانوں کے بچے جنت میں جائیں گے کیونکہ وہ مکلّف نہیں (المنھاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج کتاب القدر باب معنی کل مولود یولد علی الفطرة)لیکن بعض نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی مندرجہ ذیل حدیث کی وجہ سے توقف کیا ہے.حدیثوں میں آتا ہے ایک انصاری بچہ ایک دفعہ مر گیا جب یہ خبر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہاکے گھر میں پہنچی تو آپ نے فرمایا طُوْبٰی لَہٗ عُصْفُوْرٌ مِنْ عَصَافِیْرِ الْجَنَّۃِ کہ کیا برکت والا انجام ہے یہ جنت کی چڑیوں میں سے ایک چڑیا تھی لَمْ یَعْمَلِ السُّوْٓئَ وَلَمْ یُدْرِکْہُ.کہ نہ کوئی بُرا عمل کیا اور نہ کسی بُرے عمل کی عمر تک پہنچا.قَالَ صَلَی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ اَوْغَیْرَ ذَالِکَ.رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم نے یہ سُن کر فرمایا کہ یا پھر وہ دوزخی ہے.پھر آپ نے فرمایا یَاعَائِشَۃُ اِنَّ اللّٰہَ خَلَقَ لِلْجَنَّۃِ اَھْلًا خَلَقَھُمْ لَھَا وَھُم فِیْ اَصْلَابِ اٰبَآئِ ھِمْ وَخَلَقَ لِلنَّارِ اَھْلًا خَلَقَھُمْ لَھَا وَھُمْ فِیْ اَصْلَابِ اٰبَآئِ ھِمْ.یعنی اے عائشہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے مناسب حال کچھ لوگوں کو پیدا کیا ہے اور اُن کو اس وقت سے اُس نے جنت کا اہل بنا دیا ہے جبکہ وہ ابھی اپنے باپ دادا کی پیٹھوں میں تھے اور کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دوزخ میں داخل کرنے کے لئے پیدا کیا ہے اور ان کو اُس وقت سے دوزخ کا مستحق قرار دے دیا ہے جب کہ وہ ابھی اپنے آباء کی پیٹھوں میں تھے(مسلم کتاب القدر باب معنی کل مولود یولد علی الفطرة).جو لوگ اِس بات کے قائل ہیں کہ مومنوں کی اولاد مرنے کے بعد جنت میں جاتی ہے وہ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ شاید رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم کا یہ مطلب ہو گا کہ بے دلیل بات سے قطعی نتیجہ نہیں نکالنا چاہیے.تم نے جو کچھ کہا ہے وہ ایک استدلال ہے اس استدلال پر اپنے عقیدہ کی بنیاد کیوں رکھتی ہو.اور بعض کہتے ہیں کہ شائد رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم نے انکشاف حقیقت سے پہلے یہ فرمایا ہو.جب آپ پر انکشاف حقیقت ہو گیا.اور آپ کو معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کا کیا منشاء ہے تو آپؐ نے اپنے اس عقیدہ کو بدل لیاچنانچہ وہ اس انکشافِ حقیقت کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ بعد میں رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَامِنْ مُسْلِمٍ یَّمُوْتُ لَہٗ ثَلَاثَۃٌ مِّنَ الْوَلَدِ لَمْ یَبْلُغُوا الْحِنْثَ اِلَّا اَدْخَلَہُ اللّٰہُ تَعَالَی الْجَنَّۃَ بِفَضْلِ رَحْمَتِہٖ اِیَّاھُمْ کہ کوئی ایسا مسلمان نہیں کہ جس کے تین بیٹے مرے ہوں اور وہ ایسی عمر کو ابھی
Page 324
نہ پہنچے ہوں جس میں انسان گنہگار ہوتا ہے مگر اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور رحمت سے ان سب کو جنت میں داخل کر دے گا(سنن نسائی کتاب الجنائز باب من یتوفی لہ ثلاثة.روح المعانی زیر آیت ھذا).اَدْخَلَہُ اللّٰہُ تَعَالَی الْجَنَّۃَبِفَضْلِہٖ وَبِرَحْمَتِہٖ اِیَّاھُمْ وہ بھی اور اس کی اولاد بھی سب جنت میں چلے جائیں گے.یہ حدیث صاف بتاتی ہے کہ مومنوں کی اولاد جنت میں جائے گی.جب آپؐ نے انصاری لڑکے کے متعلق فرمایا کہ تم کیوں کہتی ہو وہ جنت کی چڑیوں میں سے ایک چڑیا ہے تو معلوم ہوتا ہے اُس وقت تک ابھی آپ پر اس کے متعلق انکشاف نہیں ہوا تھا.کفار و مشرکین کے بچوں کی نجات و عدم نجات کے متعلق تین مذاہب باقی رہے کفار و مشرکین کے بچے.سو اُن کے متعلق تین مذاہب ہیں.اکثر کہتے ہیں کہ وہ دوزخ میں جائیں گے اور اُن کا استدلال اسی حدیث سے ہے جس کا اوپر ذکر کیا جا چکا ہے کہ اَللّٰہُ اَعْلَمُ بِمَا کَانُوْا عَامِلِیْنَ.دوسرا گروہ اس کی نسبت خاموش ہے وہ کہتا ہے ہمیں کیاپتہ کہ کیا ہو گا.یہ قیامت سے تعلق رکھنے والی بات ہے اس لئے ہم اس میںدخل نہیں دے سکتے.تیسرا گرو ہ کہتا ہے کہ وہ جنّتی ہیں اور وہ کئی دلیلوں سے استدلال کرتے ہیں.اُن میں سے زیادہ تر انحصار اُن کا اس حدیث پر ہے کہ رسول کریم صلے اللہ علیہ وآلہٖ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ بچوں کو لے کر ایک بڑے درخت کے نیچے جنت میں بیـٹھے ہیں اور ان بچوں کو کھلا رہے ہیں لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ! وَاَوْلَادُ الْمُشْرِکِیْنَ کہ کیا مشرکوں کی اولاد بھی اس میں شامل ہے؟ قَالَ وَاَوْلَادُ الْمُشْرِکِیْنَ آپ نے فرمایا ہاں مشرکین کی اولاد بھی اس میں شامل ہے (بخاری بحوالہ روح المعانی زیر آیت ھذا) اسی طرح اس آیت سے بھی استدلال کیا جاتا ہے کہ وَ مَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلًا(بنی اسرائیل:۱۶) یعنی جب تک بعثتِ رسول نہ ہو جائے عذاب نازل نہیں ہو سکتا اور چونکہ بچوں کی طرف رسول کی بعثت نہیں ہوتی کیونکہ وہ مکلّف نہیں.بعثتِ رسول اُسی کی طرف ہوتی ہے جو مکلّف ہو اس لئے معلوم ہوا کہ اُن کو کوئی عذاب نہیں ہو گا.اِن تین مذاہب کے علاوہ بعض اور مذاہب بھی ہیں.چنانچہ اُن میں سے ایک یہ ہے کہ بچے جنّت اور دوزخ کے درمیان عالمِ برزخ میں رہیں گے اور ایک یہ مذہب ہے کہ اُن کا دوبارہ امتحان ہوگا اور اس کے نتیجہ کے مطابق وہ جنت و دوزخ میں جائیں گے اور وہ امتحان اس طرح ہو گا کہ انہیں کہا جائے گا کہ جائو دوزخ میں چلے جائو.جو دوزخ میں جانے پر راضی ہو جائیں گے وہ مطیع ہوں گے اور جنت میں بھیج دئے جائیں گے اور جو دوزخ میں جانے سے انکار کریں گے وہ کافر قرار دئے جا کر دوزخ میں ڈال دئے جائیں گے.چنانچہ وہ لوگ اس حدیث سے بھی جو اُوپر گزر چکی ہے کہ رسول کریم صلے اللہ علیہ وآلہٖ وسلم نے اُن کے متعلق فرمایا وَاللّٰہُ اَعْلَمُ بِمَا کَانُوْا عَامِلِیْنَ یہی
Page 325
استدلال کرتے ہیں.وہ کہتے ہیں ان الفاظ میں ابہام سے کام لیا گیا ہے آخری نتیجہ بیان نہیں کیا.رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم نے محض یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ اگر انہیں تبلیغ پہنچتی تو وہ کیا کرتے یعنی اُس وقت انہوں نےجو جو اعمال کرنے تھے وہ خدا تعالیٰ کے علم میں ہیں اور وہ جانتا ہے کہ اُن کا انجام کیا ہوتا.پس اس حدیث سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ اُن کے متعلق فیصلہ ہو چکا ہے بلکہ حدیث اپنے الفاظ کے ذریعہ اس بات کو ظاہر کر رہی ہے کہ ان کو موقعہ ملنے پر جو کچھ انہوں نے کرنا تھا اللہ تعالیٰ اُسے جانتا ہے.امام ابن تیمیہ نے اسی جواب کو ترجیح دی ہے(روح المعانی زیر آیت ھذا).اس خیال کی ان احادیث سےبھی تائید ہوتی ہے کہ پاگل، فاترالعقل اور وہ بڈھے جن کے ہوش وحواس ٹھکانے نہیں رہتے اُن کی طرف اللہ تعالیٰ اگلے جہان میں دوبارہ نبی مبعوث کرے گا(مسند احمد بن حنبل حدیث الاسود بن سریع ).امام سیوطی نے بھی اسی خیال کو ترجیح دی ہے مگرا س کے ساتھ ہی انہوں نے اپنے ایک اور خیال کا بھی اظہار کیا ہے کہ بچوں کا حشرتو ہو گا لیکن بچہ چونکہ مکلّف نہیں اس لئے وہ کہتے ہیں مشرکین کے بچے زندہ تو کئے جائیں گے لیکن پھر جانوروں کی طرح مٹی کر دئے جائیں گے.اس استدلال پر وہ اِذَا الْمَوْءٗدَةُ سُىِٕلَتْ والی آیت سے ہی مجبور ہوئے ہیں کیوںکہ اس میں یہ ذکر آتا ہے کہ مَوْئٗ دَۃُ کے بارہ میں سوال کیا جائے گا اور یہ سوال اُس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اُسے زندہ نہ کیا جائے پس وہ اس امر کو تسلیم کرنے پر مجبور ہوئے ہیں کہ بچوں کو بھی دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور اُن کے بارہ میں مجرموں سے دریافت کیا جائے گا کہ انہوں نے ان کو کس قصور کی بناء پر زندہ درگور کیا تھا.یہ ایسی ہی بات ہے جیسے حدیثوں میں آتا ہے کہ ایک بکری جس نے دوسری بکری کو دنیا میں سینگ مارا ہو گا قیامت کے دن ان کو بھی زندہ کیا جائے گا اور جسے سینگ مارا گیا ہو گا اُسے کہا جائے گا کہ وہ دوسری کو سینگ مارے(مسلم کتاب البر والصلة الآداب.باب تحریم الظلم).پس وہ اس آیت سے یہ بات ماننے پر مجبور ہوئے ہیں کہ بچوں کا بھی حشر ہو گا مگر وہ کہتے ہیں چونکہ بچے اپنی ذات میں جنّت کے مستحق نہیں ہو ں گے اس لئے ان سوالات کے بعد ان کو مٹی کر دیا جائے گا جیسے جانوروں کو اُن کا حق دلانے کے بعد فنا کر دیا جائے گا.حضرت امام احمد صاحب سرہندی نے امام سیوطی کی آخری رائے کی تائید کی ہے کہ بچے زندہ تو ہوں گے مگر پھر انہیں فنا کر دیا جائے گا.(تفسیر روح المعانی زیر آیت ھذا) جن لوگوں نے بچوں کو جنتی قرار دیا ہے اُن میں اِس بات پر بحث ہوئی ہے کہ بچے جو جنّتی ہوں گے تو آخر کسی استحقاق کے ماتحت تونہیں ہوں گے کیوں کہ انہوں نے کوئی عمل نہیں کیا ہو گا پھر جنت میں اُنہیںکیوں رکھا جائے گا.اس پر بعض کہتے ہیں کہ یہ خدا کی دین ہے وہ جس طرح چاہے کرےاس میں کسی انسان کو دخل دینے کا کیا حق ہے اور
Page 326
بعض کہتے ہیں کہ وہ جنت میں خدّام کے طور پر ہوں گے اور ماں باپ اُن کو دیکھ دیکھ کر خُوش ہوں گے پس وہ وہاں بطور استحقاق کے نہیں جائیں گے بلکہ کام اور خدمت کے لئے جائیں گے.(اوپر کے اقوال و احادیث تفسیر روح المعانی سے نقل کی گئی ہیں) اسی طرح مسند اما م احمد بن حنبل میں ایک روایت آتی ہے جس کی آخری راویہ ایک عورت ہیں یعنی خنساء کی چچی یا پھوپھی ان سے روایت ہے کہ وہ کہتی ہیں قُلْتُ یَارَسُوْلَ اللّٰہِ مَنْ فِی الْجَنَّۃِ.میں نے کہا یا رسول اللہ جنت میں کون کون جائے گا؟ قَالَ اَلنَّبِیُّ فِی الْجَـنَّۃِ آپ نے فرمایا نبی جنت میں جائے گا وَالشَّھِیْدُ فِی الْجَـنَّةِ اور شہید جنت میں جائے گا وَالْمَوْلُوْدُ فِی الْجَـنَّةِ اور چھوٹا بچہ بھی جنت میں جائےگا وَالْمَوءٗ دَۃُ فِی الْجَنَّۃِ اور موؤدۃ بھی جنت میں جائے گی.اسی طرح ابن ابی حاتم نے حسن سے مرسل روایت کی ہے قِیْلَ یَارَسُوْلَ اللّٰہِ مَنْ فِی الْجَنَّۃِ قَالَ اَلْمَوْئٗ دَۃُ فِی الْجَنَّۃِ آپ سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ جنت میں کون جائے گا؟ آپ نے فرمایا موء ٗدہ جنت میں جائے گی.اسی طرح ابن ابی حاتم نے ابن عباسؓ سے بھی یہ روایت کی ہے کہ اَطْفَالُ الْمُشْرِکِیْنَ فِی الْجَنَّۃِ فَمَنْ زَعَمَ اَنَّـھُمْ فِی النَّارِ فَقَدْ کَذَبَ یَقوْلِ اللّٰہِ تَعَالٰی وَاِذَا لْمَوئٗ دَۃُ سُئِلَتْ بِاَیِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ(ابن کثیر زیر آیت ھذا).یہ وہ پرانے اقوال ہیں جو مومنوں اور مشرکوں کے بچوں کے متعلق ہمیں احادیث اور آئمہ سابقین کی کتب میں سے ملتے ہیں ان سے ظاہر ہے کہ مومنوں کے بچوں کے جنت میں جانے کے متعلق قریبًاقریبًاتمام مسلمانوں کا اتفاق ہے.صرف دو حدیثیں ایسی ہیں کہ اگر وہ صحیح ہوں تو اس مسئلہ کو کسی قدر مشتبہ کر دیتی ہیں.جن میں سے ایک وہ حدیث ہے جس میں حضرت خدیجہؓ کی طرف یہ بات منسوب کی گئی ہے کہ انہوں نے رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرے دو بچے جوجاہلیت میں مر گئے تھے اُن کا کیا حال ہے آپ نے فرمایا وہ دوزخ میں ہیں.پس یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر مومنوں کے بچے بہر صورت جنت میں جائیں گے تو حضرت خدیجہؓ کے ایک سوال کے جواب میں رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا کہ وہ دونوں بچے دوزخ میں ہیں.اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنھاکے متعلق روایت آتی ہے کہ جب آپ نے ایک انصاری بچے کے متعلق فرمایا کہ اس کا انجام بڑا مبارک ہوا ہے وہ جنت کی چڑیوں میں سے ایک چڑیا تھی.تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَوْ غَیْرَ ذَالِکَ یا شاید وہ دوزخی ہو اور پھر یہ دلیل بھی دی کہ اِنَّ اللّٰہَ تَعَالٰی خَلَقَ لِلْجَنَّۃِ اَھْلًا خَلَقَھُمْ لَھَا وَھُمْ فِیْ اَصْلَابِ اٰبَآئِ ھِمْ وَخَلَقَ لِلنَّارِ اَھْلًا خَلَقَھُمْ لَھَا وَھُمْ فِیْ اَصْلَابِ اٰبَآئِ ھِمْ (مسلم کتاب القدر باب معنی کل مولود یولد علی الفطرة و حکم
Page 327
موت اطفال)جب تک اِن دونوں حوالوں کو ہم حل نہ کر لیں اُس وقت تک کسی صحیح نتیجہ پر نہیں پہنچ سکتے.اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنھاکی یہ روایت کہ بعض لوگ جنت کے لئے پیدا کر دیئے گئے ہیں اور بعض لوگ دوزخ کے لئےدرست ہے، تو ہم ایک مومن کے بچہ کے متعلق بھی یہ یقینی طور پرنہیں کہہ سکتے کہ وہ جنّتی ہے یا دوزخی.اور اس طرح سارا استدلال باطل ہو جاتا ہے.جیسا کہ میں بتا چکا ہوں محدثین نے اس کے یہ معنے کئے ہیں کہ یہ پہلے کی بات ہو گی.جب رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم پر ابھی انکشاف حقیقت نہیں ہوا تھا جب انکشاف ہو گیا تو آپ نے اپنے عقیدہ کو بدل دیا.مگر اس میں ایک اور مشکل یہ پیش آجاتی ہے کہ حدیثوں میں ہی ذکر آتا ہے کہ رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ بچوں کو لے کر ایک جگہ جنت میں بیٹھے ہیں اور آپ نے فرمایا کہ ان بچوں میں مشرکین کے بچے بھی تھے.یہ واقعہ معراج سے تعلق رکھتا ہے اور معراج کی حدیث ۵ بعد دعویٰ نبوت کی ہے گویا ہجرت سے آٹھ سال پہلے یہ انکشاف آپ پر ہو چکا تھا.حضرت عائشہ رضی اللہ عنھاکی شادی ہجرت سے ایک سال بعد ہوئی ہے اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ نو سال قبل اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر یہ انکشاف ہو چکا تھا اور جب اس کی طرف سے انکشاف ہو چکا تھا تو رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم کس طرح ایسی بات کہہ سکتے تھے جو اس انکشاف کے خلاف ہوتی.پس یہ جواب بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا.بہرحال جہاں تک احادیث کا تعلق ہے وہ ہمیں ایک دوسری سے ٹکراتی ہوئی ملتی ہیں اور جب وہ ایک دوسری سے ٹکراتی ہوئی نظر آتی ہیں تو ہمیں قرآن شریف کی طرف توجہ کرنی چاہیے اور غور کرنا چاہیے کہ اس بارہ میں وہ کیا تعلیم پیش کرتا ہے کیونکہ قرآن شریف وہ کلام ہے جو خدا تعالیٰ نے نازل کیا اور جسے بغیر کسی خطرہ کے ہم قبول کرنے کے لئے تیار ہو سکتے ہیں.بے شک حدیثوں میں سے بعض ایسی ہیں جو صحاح میں آئی ہیں اور وہ بڑے پایہ کی ہیںمگر بہرحال حدیثوں میں یا تو خلط ہو گیاہے اور یاپھر و ضاعین نے وضع کی ہیں اس لئے ہم اس مسئلہ کی حقیقت معلوم کرنے کے لئے قرآن شریف کی طرف توجہ کرتے ہیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِۚ (آل عمران:۱۸۳)کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا.اور جب وہ ظلم نہیں کرتا تو یہ کس طرح سمجھاجاسکتا ہے کہ وہ بچوں کو بغیر قصور کے دوزخ میں داخل کر دے گا.وہ شخص جس نے کوئی فعل کیا ہی نہیں اور جو مکلّف ہی نہیں ہوا اس کو سزادینا تو قطعی طور پر ظلم ہے.دوسری جگہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَ مَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلًا (بنی اسرائیل:۱۶)کہ ہم بغیر بعثتِ رسول کے لوگوں کو عذاب نہیں دیا کرتے محدثین نے بھی اس آیت سے استدلال کر کے بچوں کو بری قرار دیا ہے.پس ایک طرف اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ ہم اپنےبندوں پر ظلم نہیں کرتے اور
Page 328
دوسری طرف یہ فرمانا کہ جب تک ہم رسول بھیج کر لوگوں پر اپنی حجت تمام نہ کر لیں ان کو اپنے عذاب میں مبتلا نہیں کرتے بتلا رہا ہے کہ بچے عذاب کے مورد نہیں ہو سکتے کیونکہ نہ انہوں نے کوئی جرم کیا اور نہ ان کی طرف بعثتِ رسول ہوئی.اسی طرح فرماتا ہے وَ لَوْ اَنَّاۤ اَهْلَكْنٰهُمْ بِعَذَابٍ مِّنْ قَبْلِهٖ لَقَالُوْا رَبَّنَا لَوْ لَاۤ اَرْسَلْتَ اِلَيْنَا رَسُوْلًا فَنَتَّبِعَ اٰيٰتِكَ مِنْ قَبْلِ اَنْ نَّذِلَّ وَ نَخْزٰى (طٰہٰ :۱۳۵) یعنی اگر ہم قرآن اتارنے سے پہلے کسی عذاب سے ان لوگوں کو ہلاک کر دیتے.تو بے شک یہ کہتے کہ اے ہمارے پروردگار تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے ہم تیرے حکم پر چلتے.اسی مضمون کو ایک اور جگہ ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے کہ يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلٰى فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا جَآءَنَا مِنْۢ بَشِيْرٍ وَّ لَا نَذِيْرٍ١ٞ فَقَدْ جَآءَكُمْ بَشِيْرٌ وَّ نَذِيْرٌ١ؕ وَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ(المائدة:۲۰)یعنی اے اہل کتاب جب رسولوں کے آنے میں مدتوں تک ناغہ رہا تو ہمارا رسول تمہارے پاس آیا جو احکام الٰہی تم سے صاف صاف بیان کرتا ہے اور ہم نے یہ رسول اس غرض سے بھیجا کہ مبادا کل کو کہیں تم کہنے لگوکہ ہمارے پاس نہ تو کوئی نجات کی خوشخبری سنانےوالا اور نہ عذاب الٰہی سے ڈرانے والا آیا تو اب تو تم کو اس عذ ر کی بھی گنجائش نہیں رہی.کیونکہ تمہارے پاس خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا آچکا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے.اس آیت میں اللہ تعالیٰ حجتِ صحیحہ اس بات کو قرار دیتا ہے کہ کسی نبی کی پہلے بعثت ہو اور پھر لوگ یا اُس کی تکذیب کریں اور یا اس پر ایمان لے آئیں.کیوں کہ فرماتا ہے ہم نے اسی لئے تمہاری طرف نبی بھیجے ہیں تا کہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہہ دو کہ ہماری طرف کوئی رسول نہیں آیا تھا.گویا باوجود اس کے کہ ان میں عقل موجود تھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر ہم تمہاری طرف نبی نہ بھیجتے تو ہم تم کو بری سمجھتے جب بڑی عمر کے آدمی بھی نبی کی بعثت کےبغیر بری سمجھے جا سکتے ہیں تو اُن بچوں کو جو نبی کی حقیقت سمجھنے کے قابل ہی نہیں اور جو احکامِ شریعت کے مکلّف ہی نہیں اُن کو ملزم قرار دینا اور کہنا کہ وہ دوزخ میں جائیں گے یقیناً قرآن کریم کے خلاف ہے.قرآن کریم نے یہ اصول رکھا ہے کہ جس شخص میں عقل موجود ہے مگر نبی اس کی طرف نہیں آیا وہ بھی مجرم نہیں.پھر جس میں عقل وفہم کا مادہ بھی نہ ہو وہ کس طرح مجرم قرار دیا جا سکتا ہے؟ بہرحال قرآن ان معنوں کو ردّ کرتا ہے.جب اللہ تعالیٰ عقلمندوں کو بھی نبی کی بعثت کے بغیر قابلِ سرزنش قرار نہیں دیتا تو جن پر رسول کی موجودگی میں بھی حجت نہیں ہو سکتی تھی ان کو کس طرح عذاب مل سکتا ہے.پس قرآن کریم کی آیات سے صاف پتہ لگتا ہے کہ یہ عقیدہ بالکل غلط ہے کہ بچے دوزخ میں جائیںگے.اب رہا یہ سوال کہ اگر بچے مکلّف نہیں ہیں تو پھر مومنوں اور کفار کے بچوں کا کیا حال ہو گا؟ اس کے متعلق یاد رکھنا چاہیے کہ جہاں تک مومنوں کے بچوں کا سوال ہے حدیث معراج اس کی تائید میں ہے کہ وہ جنت میں
Page 329
جائیں گے اور عقل بھی یہی کہتی ہے کہ حدیثِ معراج بڑے پایہ کی ہے اور بڑے تواتر سے آتی ہے اور مختلف اَسناد سے آتی ہے اور گو اس میں بعض مقامات پر اضطراب بھی پایا جاتا ہے لیکن اصولی طور پر حدیثِ معراج کی طرف محدثین کی بڑی نظر پڑی ہے.پس حدیثِ معراج اس بات کی دلیل ہے کہ مومنوں کے بچے جنت میں رکھے جائیں گے.دوسرے عقلی طورپر ہم دیکھتے ہیںکہ مومن کی تسلّی اور اسکی خوشی کے لئے جنت میں اُس کے بچوں کا ہونا نہایت ضرورری ہے اللہ تعالیٰ جنّتیوں کے متعلق فرماتا ہے لَھُمْ فِیْھَا مَا یَشَآءُ وْنَ (النحل :۳۲) وُہ اُس میں جو کچھ چاہیں گے اُن کو مل جائے گا اور جب یہ صورت ہے تو ایک ماں تو سب سے پہلے یہ خواہش کرے گی کہ میرا بچہ مجھے واپس دے دو.ہم نے دیکھا ہے جب کوئی عورت مرنے لگتی ہے تو وہ اُس وقت کہتی ہے کہ میرا بچہ جو مر چکا ہے میں اب اُس سے جا کر ملوں گی.پس عقل بھی اس بات کی تائید کرتی ہے کہ عورتوں کی تسلّی اور ان کے اطمینان کے لئے اُن کے بچے اُنہیں ملنے چاہئیں چاہے وہ کسی صورت میں ملیں.یہ بحث نہیں وہ خواہ خدم کے طور پر ملیں یا کھلونے کے طور پر، بہرحال ملنے چاہئیں سوائے اس کے جو دوزخی ہو اور خُدا اوراس کے رسول کا مخالف ہوکیونکہ ایسے لڑکے سے مومن اپنے تعلق کوکاٹ دے گا اور اس کے دل میں یہ خیال بھی نہیں آئے گا کہ وُہ اس سے ملے.بہرحال اگر کوئی لڑکا بالغ ہے اور پھر کافر اور مشرک ہے تب تو کوئی اعتراض نہیں اللہ تعالیٰ اُسے جہاں چاہے رکھے ایک مومن کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا اور نہ اُسے کوئی دُکھ ہو سکتا ہے کیونکہ اُس کی محبت وہ اپنے دل سے نکال دیتا ہے لیکن جو بچہ بالغ نہیں جو معصومیت کی حالت میں فوت ہوا ہے.عقل اور فطرت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اُسے اپنے ماں باپ کے پاس جنت میں رکھا جائے بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ جنت اسی صورت میں جنت ہو سکتی ہے جب ماں کے پاس اس کے بچے موجود ہوں.اس عقلی تائید کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ حدیثِ معراج عین فطرت کے مطابق ہے.باقی رہے کفار و مشرکین کے بچے سو گو بعض حدیثیں اس بات کی تائید میں ہیں کہ وہ دوزخ میں جائیں گے لیکن بعض ایسی بھی حدیثیں ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے جیسا کہ حدیثِ معراج میںہی اولادالمشرکین کا بھی ذکر آتا ہے مگر یہ مسئلہ ایسا اہم نہیں.جہاں تک مومن کی اولاد کا مسئلہ ہے بیشک وہ اہم ہے.لیکن جہاںتک مشرکوں کی اولاد کا مسئلہ ہے وہ اپنے اندر کوئی اہمیت نہیں رکھتا.اگر یہ فیصلہ ہو کہ اولادِ مشرکین کے جنت میں جانےوالی حدیثیں بھی صحیح ہیں اور دوزخ میں جانے والی حدیثیں بھی صحیح ہیںتو رَحْمَتِیْ وَسِعَتْ کُلَّ شَیْءٍ (الاعراف:۱۵۷)کے مطابق ہم اُن کے جنت میں جانے والی حدیثوں کو ترجیح دےدیں گے کیونکہ قرآن نے یہ اصول بتا دیا ہے کہ جب دو چیزیں ٹکرا جائیں تو جس میں رحمت کا پہلو زیادہ ہو وہ لے لو.کیونکہ خدا کی رحمت اُس کے
Page 330
غضب پر غالب ہوتی ہے.پس اگر دونوں حدیثیں رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہوں اور ہم کوئی فیصلہ نہ کر سکیں کہ ان میں سے کن کو ترجیح دی جائے تو درائت یہی کہے گی کہ رَحْمَتِیْ وَسِعَتْ کُلَّ شَیْءٍ کے اصول کے مطابق جنت میں جانے والی حدیثوں کو ترجیح دے دو.لیکن اگر یہ نہ ہو تو میرے نزدیک اس بات کو مدنظر رکھ کر کہ دوزخی جب جنت میں جائے گا تو اس کا وہ مقام نہیں ہو سکتا جو براہِ راست جنت میں جانے والے کا ہو سکتا ہے یہ ممکن ہے کہ شروع سے جنتی اور بعد میں جنت میں جانےوالے میں یہ ایک امتیاز ہو کہ شروع سے جنتی کی صغیر اولاد بھی اُس کے پاس رکھی جائے خواہ ایک تابع کی شکل میں.اور بعد میں آنے والے کی صغیر اولاد فنا کر دی جائے کیونکہ وہ اپنی ذات میں مستحق نہیں اور بالواسطہ استحقاق کا فائدہ اُسے پہنچا نہیں.قیامت کو بچوں کی طرف نبی کی بعثت اگرا س حدیث کو اصل قرار دے لو جس میں رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بچوں کی طرف دوبارہ نبی مبعوث ہو گا (دیکھو مسند احمد بن حنبل حدیث اسود بن سریع بحوالہ روح المعانی زیر آیت مَاکُنَّا مُعَذِّبِیْنَ حَتّٰی نَبْعَثَ رَسُوْلًا) تو پھر یہ بحث ہی فضول ہے کیونکہ اس کو صحیح تسلیم کرنے کی صورت میں نہ مومنوں کے بچوں کا سوال رہتا ہے اور نہ کافروں کے بچوں کا سوال رہتا ہے.پھر حدیث معراج کے یہ معنے ہوں گے کہ یوم البعث تک تو تمام بچے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس رہیں گے اور وہ جنت کا کھلونا بنے رہیں گے پھر ان کی طرف نبی مبعوث کیا جائے گا اور وہ اس پر ایمان لا کر یا اس کی تکذیب کر کے جنت یا دوزخ میں چلیں جائیں گے.لیکن اگراس حدیث کے کوئی دوسرے معنے کئے جائیں.جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اسی کو ترجیح دی ہے کہ فطرتی ایمان پر وہاں فیصلہ کر دیا جائے گا تو پھر اس امر کو مدنظر رکھتے ہوئے کہ دوزخی نے تو بہرحال دوزخ میں جانا ہے اگر یہ مان لیا جائے کہ اس کی صغیر اولاد کو بطور ترحم مٹا دیا جائے گا تو اس میں کوئی ظلم نہیں.مومنوں کے بچوں کا ان کی دلجوئی کے لئے کسی شکل میں جنت میں جانا عین رحم ہے لیکن کافر چونکہ اپنے دل کا چَین دوزخ میں پہلے ہی کھو چکا ہو گا اس لئے اس کی صغیر اولاد کو مٹا دیا جائے گا اور یہ اس پر رحم ہو گا ظلم نہ ہو گا گویا مومنوں کی صغیر اولاد تو اپنے ماں باپ کے ساتھ جنت میں رکھی جائے گی لیکن کفار کی صغیر اولاد جانوروں کی طرح مٹی کر دی جائے گی ان معنوں کو تسلیم کرنے کی صورت میں دونوں اقوال میں تطبیق ہو جاتی ہے اور حضرت امام احمد صاحب سرہندی کی رائے سب سے زیادہ صحیح اور درست معلوم ہوتی ہے.مومنوں کے چھوٹے فوت شدہ بچوں کا جنت میں مقام باقی رہا یہ کہ وہ جنت میں کس حیثیت سے رہیں گے؟ یہ صرف ایک علمی سوال ہے.ورنہ جس طرح خدا چاہے رکھے اس میں ہمارا کیا دخل ہو سکتا ہے مگر مجھے قرآن کریم
Page 331
کی دو آیتوں پر غور کرنے سے معلوم ہوا ہے کہ نعماء جنت سے پوری طرح متمتع ہونے والے وجود صرف بالغ ہی ہوں گے.دوسرے صرف دلجمعی کے لئے جنتیوں کے پاس رکھے جائیں گے پہلے میں سمجھتا تھا کہ جس طرح ماں باپ جنت میں جائیں گے اسی طرح بچے جنت میں رکھے جائیںگے مگر اب مجھے قرآن پر غور کرنے سے معلوم ہوا ہے کہ گو چھوٹے بچے بھی جنت میں رکھے جائیں گے مگر ان کی حیثیت میں کسی قدر فرق ہو گا.اِن دو آیتوں میں سے جن سے مومنوں کے بچوں کے جنت میں مختلف حیثیت میں جانے کا پتہ ملتا ہے پہلی یہ ہے وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ اتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِاِيْمَانٍ اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَ مَاۤ اَلَتْنٰهُمْ مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ (الطور:۲۲) یعنی جو لوگ ایمان لے آئے اور اُن کی اولاد ایمان میں اُن کی تابع ہو چکی ہے ان کی اولاد کو بھی ہم اُن سے ملا دیں گے اور اُن کے عمل سے ہم کچھ کم نہ کریں گے.اسی طرح فرماتا ہے جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا۠ وَ مَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَآىِٕهِمْ وَ اَزْوَاجِهِمْ وَ ذُرِّيّٰتِهِمْ (الرعد :۲۴)یعنی ہمیشگی کے باغات ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے اور اُن کے باپ دادا میں سے جنہوں نے اعمال صالحہ کئے تھے وہ بھی ان باغات میں داخل ہوںگے اور ان کی بیبیاں اور ان کی اولاد جو نیک ہوں گے وہ بھی وہاں ہوں گے.اسی طرح ملائکہ کی دعا ہے رَبَّنَا وَ اَدْخِلْهُمْ جَنّٰتِ عَدْنِ ا۟لَّتِيْ وَعَدْتَّهُمْ وَ مَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَآىِٕهِمْ وَ اَزْوَاجِهِمْ وَ ذُرِّيّٰتِهِمْ(المومن :۹) یعنی اے ہمارے رب انہیں ہمیشہ رہنے کے باغوں میں داخل کر جن کے دینے کا تُو نے وعدہ کیا ہے اور اُن کے باپ دادا اور اُن کی بیبیوں اور اولاد میں سے جو نیک ہوں اُن کو بھی جنت میں داخل فرما.اِن ساری جگہوں میں مَنْ صَلَحَ یا بِاِیْمَانٍ وغیرہ کے الفاظ آتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ چھوٹے بچوں اور دوسروں کا جنت میں جانا اپنے اندر کچھ فرق ضرور رکھتا ہے.چونکہ اُن کی ارواح کوپورا ارتقاء حاصل نہیں ہو گا اس لئے ان کا جنت میں جانا بطوراستحقاق نہیں ہو گا بلکہ اپنے ماں باپ کی خوشی کے لئے ہو گا اس لئے مفسرین کا ذہن اس طرف گیا ہے کہ اُن بچوں کو وہاں خدم کے طور پر رکھا جائے گا لیکن میں ان کا نام خدم نہیں رکھتا بلکہ کھلونا رکھتا ہوں.میرے نزدیک ان کی ارواح ایسی ترقی یافتہ نہیں ہوں گی کہ وہ جنت کی لذتوں سے پوری طرح متمتع ہو سکیں.دوسرے جنتیوں کے متعلق تو آتا ہے کہ ملائکہ جنت کے ہر دروازہ سے ان کے پاس آئیں گے اور کہیں گے سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ(الرعد:۲۵) کہ تم پر سلامتی ہو اس کے بدلے میں جو دنیا میں تم صبر کرتے رہے ہو یہ سب انعام اُسی کا صلہ ہے.پس دیکھو دار آخرت کا بدلہ کیسا اچھا ہے.مگر ملائکہ کایہ سلام انہی لوگوں کو ہو سکتا ہے جو مَنْ اٰمَنَ میں داخل ہوں یا مَنْ صَلَحَ میں داخل ہوں.پس چونکہ ان آیات میں اِتَّبَعَتْھُمْ ذُرِّیَّتُھُمْ بِاِیْمَانٍ اور مَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَآئِ ھِمْ وَاَزْوَاجِھِمْ وَ ذُرِّیَّاتِھِمْ وغیرہ کے الفاظ آتے ہیں.اور چھوٹے بچے نہ ایمان لاتے ہیں نہ اعلیٰ کی
Page 332
صلاحیتیں اُن میں ہوتی ہیں اس لئے ان کو جنت میں وہ مقام حاصل نہیں ہو سکتا جو دوسروں کو حاصل ہو گا.پس جو بالغ ہوں گے یا بڑی عمر کے ہوں گے وہ تو جنت میں استحقاق کے طور پر جائیں گے مگر جو بچے چھوٹی عمر میں فوت ہو چکے ہوں گے وہ اگر بغیر کسی مزید امتحان کے جنت میں گئے تو صرف اپنے ماں باپ کا دل خوش کرنے کے لئے وہاں رکھے جائیں گے اور ان کی دلجمعی کا سامان ہوں گے خواہ کسی شکل اور کسی درجہء روحانیت میں اُن کو داخل کیا جائے یہ ایک الٰہی راز ہے اس میں پڑنے کی ہم کو ضرورت نہیں.پہلے میرا ذہن اِدھر نہیں جاتا تھا اور میں حیران ہوتا تھا کہ وہاں بچوںکو خدم کے طور پر کیوں رکھا جائے گا مگر اِن آیات پر غور کرنے سے مجھے معلوم ہوا کہ خواہ ان کا نام خدم رکھ لو.خواہ کھلونا کہہ لو بہرحال چونکہ پورے طور پر اُن کی ارواح کا ارتقاء نہیں ہوا ہو گا اس لئے گو وہ مومنوں کے ساتھ ہی رکھے جائیں گے مگر اُن کی کیفیت جُداگا نہ ہو گی.اس جگہ ایک اور بات یاد رکھنے والی ہے کہ ضمنی طور پر یہاں سے ایک اور مسئلہ کا بھی استنباط ہوتا ہے.رسول کریم صلے اللہ علیہ وآلہٖ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص مسلمان ہو جائے اس کے کفر کے سارے گناہ مٹ جاتے ہیں یہ ایک عام مشہور مسئلہ ہے اور احادیث سے بھی اس کا پتہ چلتا ہے مگر اس مسئلہ میں کچھ ترمیم کی ضرورت ہے خواہ وہ ترمیم اصلاحی نہ ہو بلکہ تکمیل کی ہو.حدیثوں میںآتا ہے عبدالرزاق نے نعمان بن البشیر سے اور انہوں نے عمر بن الخطاب سے نقل کیا ہے کہ قیس ابن عاصم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے کچھ لڑکیاں جاہلیت میں زندہ دفن کی ہیں آپ نے فرمایا ہر موئودہ کے بدلہ میں ایک غلام آزاد کر دو.اُس نے کہا یا رسول اللہ اِنِّیْ صَاحِبُ اِبِلٍ مَیں تو صاحب الابل ہوں غلام کہاں سے لائوں اُونٹوں کے متعلق فرمائیں تو اُن کو نحر کرنے کے لئے تیار ہوں آپ نے فرمایا فَا نْحَرْ عَنْ کُلِّ وَاحِدَۃٍ مِنْھُنَّ بُدْنَۃً (ابن کثیرسورۃ التکویر زیر آیت ھذا) کہ ہر ایک کے بدلہ میں ایک اونٹ قربان کر دو.اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسے گناہ جو انسان کی فطرت پر بھاری ہوں باوجود اُن کی بخشش کے اور باوجود اسلام نصیب ہو جانے اور توبہ قبول ہو جانے کے پھر بھی اگر انسان کفارہ ادا کرتا رہے تو تکمیل روحانیت کے لئے یہ بات بہت مفید ہوتی ہے.مسئلہ عزل کے متعلق بعض احادیث اس جگہ ایک اور حدیث بھی نقل کی جاتی ہے جس پر روشنی ڈالنی ضروری ہے.امام احمد روایت کرتے ہیں کہ جذامہ بنت وہب اُخت عکاشہ نے بیان کیا قَالَتْ حَضَرْتُ رَسُوْلَ اللّٰہِ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ فِیْ نَاسٍ وَھُوَ یَقُوْلُ لَقَدْ ھَمَمْتُ اَنْ اَنْھٰی عَنِ الْغَیْلَۃِ کہ میں ایک دفعہ رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئی کچھ اور لوگ بھی ساتھ تھے آپ اُس وقت فرما رہے تھے کہ میں نے ارادہ کیا
Page 333
تھا کہ لوگوں سے کہہ دوں کہ جب عورت بچے کو دُودھ پلا رہی ہو تو مرد اُس سے صحبت نہ کیا کرے فَنَظَرْتُ فِی الرُّوْمِ وَفَارِسَ فَاِذَاھُمْ یَغَیْلُوْنَ اَوْلَادَھُمْ وَلَا یَضُرُّ اَوْلَادَھُمْ ذَالِکَ شَیْئًا.لیکن پھر میں نے روم اور فارس کو دیکھا کہ وہاں کے رہنے والے برابر یہ کام کرتے ہیں مگر ان کے بچوں کو کوئی نقصان نہیں ہوتا اس لئے میں نے اس ممانعت کا خیال ترک کر دیا ثُمَّ سَأَلُوْہُ عَنِ الْعَزْلِ.پھر انہوں نے آپ سے عزل کے متعلق پوچھا کہ اس بارہ میں آپ کا کیا حکم ہے فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّمَ ذَالِکَ الْوَأدُ الْخَفِیُّ.رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی ایک وأد خفی ہے.(مسلم کتاب النکاح باب جواز الغیلۃ و ھی وطی المرضع ) یہ روایت مسلم نے سعید بن ابی ایوب سے اور مالک بن انس سے بھی نقل کی ہے اور ابو دائود اور الترمذی اور النسائی نے یہ روایت ابی الاسود سے روایت کی ہے.اس روایت سے بعض لوگ یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ جب عزل بھی وأدخفی ہے تو یہ فعل بھی کسی سزا کا مستحق ہونا چاہیے لیکن یہ بات روایت سے درست معلوم نہیں ہوتی.مسئلہ عز ل اور اس کا جواز و عدم جواز اوّل تو اگر عزل منع ہے اس وجہ سے کہ عزل وأدخفی ہے تو پھر حاملہ سے جماع بھی منع ہونا چاہیے مگر حمل کے ایام میں جماع کی حرمت کہیں سے ثابت نہیں حالانکہ وہ وأ دقطعی اور یقینی ہے.دوسرےؔ عزل کے جائز ہونے کے متعلق بھی احادیث آتی ہیں مثلاً ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم سے عزل کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا بے شک کرو جس متنفّس کو خدا نے پیدا کرنا ہے وہ تو اُسے بہرحال پیدا کر کے رہے گا (بخاری کتاب القدر باب کان امراللہ قدراً مقدوراً )پس چونکہ عزل کا جواز بعض دوسری احادیث سے ثابت ہے اس لئے گویہ حدیث بڑے بلند پایہ کی ہے مگر میرے نزدیک اس کے یہی معنے ہیں کہ بلاضرورت ایسا کرنا ٹھیک نہیں.اگر کوئی شخص بلاضرورت ایسا کرتا ہے تو وہ وأدخفی سے کام لیتا ہے یعنی وہ شخص جس کی عزل سے غرض نسل انسانی کا انقطاع ہو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مجرم اور گنہگار ہے ورنہ اور کئی صورتیں ایسی ہو سکتی ہیں جن میں عزل ہو سکتا ہے.مثلاً ایک شخص کی بیوی بیمار ہے.وہ دوسری شادی کی توفیق نہیں رکھتا لیکن خود اُس میں خدا نے قوائے شہوانیہ پیدا کئے ہیں.دوسری طرف ڈاکٹر کہتا ہے کہ اگر عورت کو حمل ہو گیا تو اس کی جان کا خطرہ ہو گا ایسی حالت میں نہ صرف عزل جائز ہو گا بلکہ اگر حمل ہو جائے تو اُس کا نکلوا دینا بھی جائز ہو گا.حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام سے میں نے خود سنا ہے کہ ایسی حالت میں اگر کوئی عورت حمل نہیں نکلواتی اور وہ مر جاتی ہے تو ہمارے نزدیک وہ خودکشی کرنے والی ہے.آپ نے فرمایا ایسی حالت میں ضروری ہے کہ بچہ کو نکلوا دیا جائے.کیوں کہ بچہ کے متعلق تو ہمیںکچھ علم نہیں کہ اُس نے کیسا بننا ہے مگر ایک زندہ وجود ہمارے سامنے ہوتا ہے اور اُ س کی جان کی حفاظت اس
Page 334
بات کی متقاضی ہوتی ہے کہ اس کو بچایا جائے اور اس کے بچہ کو تلف ہونے دیا جائے.لیکن اگر کوئی خشیتہ املاق کی وجہ سے عزل کرتا یا حمل کونکلواتا ہے تو وہ ایک ناجائز فعل کا ارتکاب کرتا ہے.بہرحال عزل کے جواز یا عدم جواز کا فتویٰ عورت کے حالات کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اگر ضرورت کے موقع پر ایسا کیاجاتا ہے تو یہ جائز ہے.اگر بلاضرورت کیا جاتا ہے تو ناپسندیدہ ہے اور اگر نسل انسانی کے انقطاع کے لئے ایسا کیا جاتا ہے تو حرام ہے.مثلاً یوروپ والے صرف نسل انسانی کے انقطاع کے لئے ایسا کرتے ہیں اور چونکہ اس کے نتیجہ میں قوم تباہ ہو تی ہے اس لئے یہ فعل یقیناً ناجائز اور حرام ہو گا.اور اگر کوئی بلاضرورت کرتا ہے تووہ ایک مکروہ کام کرتا ہے اور اگر ضرورت حقہ پر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو وہ ایک جائز کام کرتا ہے.بہرحال اس مسئلہ کے تینوں پہلو ہیں.جب عزل کو قومی تباہی کا موجب بنا دیا جائے تو یہ حرام ہو جاتا ہے.جب عزل قومی تباہی کا موجب نہ ہو لیکن اس کی کوئی ضرورت بھی نہ ہو تو یہ مکروہ ہوتا ہے.اور جب کسی عورت کی جان بچانے کے لئے یا کسی ایسی ہی ضرورت کے لئے جسے شریعت جائز قرار دیتی ہو ایسا کیا جائے تو یہ جائز ہوتا ہے.پس ہرعزل وأدلخفی کے ماتحت نہیں آسکتا.وہی عزل اس جرم کا مرتکب بناتا ہے جو قومی تباہی کا موجب بن جائے جیسے فرانس وغیرہ ممالک میں اس کا رواج ہو رہا ہے اور جس کا نتیجہ یہ ہو ر ہا ہے کہ وہاں کی آبادی خطرناک طور پر کم ہو گئی ہے اور وہ قوم دوسروں کے مقابلہ میں بالکل مقہور اور ذلیل ہو گئی ہے اسی لئے رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تَزَوَّجُوا لْوَلُوْدَ الْوَدُوْدَ (نسائی کتاب النکاح باب کراھیۃ تزویج العقیم) کہ جو عورتیں کثرت سے بچے جننے والی ہوں اُن سے شادیاں کیا کرو کیوںکہ اس طرح قوم کی ترقی ہوتی ہے.وَ اِذَا الْمَوْءٗدَةُ سُىِٕلَتْ کو اگر قیامت پر چسپاں کیا جائے تو سُئِلَتْ کے دونوں معنے ہو سکتے ہیں (۱)وائد سے پوچھا جائے گا(۲)یا موء دہ کو دوبارہ زندہ کر کے پوچھا جائے گاخواہ بعد میں وحوش کی طرح اُسے فنا کر دیا جائے مگر بِاَيِّ ذَنْۢبٍ قُتِلَتْاسی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وائد سے پوچھا جائے گا.وَ اِذَا الْمَوْءٗدَةُ سُىِٕلَتْکی پیشگوئی کا ظہور جس طرح اس سورۃ کی اور تمام پیشگوئیاں موجودہ زمانہ میں پوری ہو چکی ہیں اسی طرح اِذَا الْمَوْءٗدَةُ سُىِٕلَتْکی پیشگوئی بھی پوری ہو چکی ہے.کیونکہ اس میں بتایا گیا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا جبکہ لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے کی قانوناً ممانعت کر دی جائے گی اور اگر کوئی ایسا کرے گا تو اُسے سزا دی جائے گی.چنانچہ ۱۸۷۲ء میں ایسا قانون حکومت انگریزی نے جاری کر دیا اور اس طرح یہ علامت بھی جو آخری زمانہ سے تعلق رکھتی تھی پوری ہو گئی.
Page 335
وَ اِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ۪ۙ۰۰۱۱ اور جب کتابیں پھیلا دی جائیں گی.حَلّ لُغَات.نُشِرَتْ نُشِرَتْ نَشَرَ سے مجہول کا مؤنث کا صیغہ ہے اور نَشَرَ الْخَبَرَ (نَشْرًا) کے معنے ہیں اَذَاعَہُ.اُس کو پھیلا دیا.اور نَشَرَ الثَّوْبَ وَالْکِتٰبَ کے معنے ہیں بَسَطَہٗ.خِلَافُ طَوَاہُ.اُس نے کپڑے اور کتاب کو کھولا.اور نَشَرَ اللّٰہُ الْمَوْتٰی کے معنے ہوتے ہیں اَحْیَاھُمْ.اللہ نے مُردوں کو زندہ کیا اور نَشَرَ الْمَوْتٰی کے معنے ہیں حَیُّوْا.مردے زندہ ہو گئے اس لحاظ سے یہ لازم بھی ہے اور متعدّی بھی (اقرب) پس وَاِذَاالصُّحُفُ نُشِرَتْ کے معنے ہوں گے جبکہ صحیفے پھیلائیں جائیں گے یا جبکہ وہ کھولے جائیں گے یا جبکہ مردہ صحیفے پھر زندہ کئے جائیں گے.تفسیر.اِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْسے مراد اخبارات اور رسالوں کی اشاعت یہ تینوں معنے اس زمانہ میں بڑی شان کے ساتھ پورے ہو رہے ہیں وَاِذَاالصُّحُفُ نُشِرَتْ کے پہلے معنے یہ تھے کہ صحیفے پھیلائے جائیں گے.یہ پیشگوئی اس طرح پوری ہوئی کہ کتابوں اور اخبارات کی اشاعت کے لئے مطابع نکل آئے ہیں.پھر ریل گاڑیاں ایجاد ہو چکی ہیں جن سے شائع شدہ اخباریں اور کتابیں سارے جہان میں پھیل جاتی ہیں دنیا میں پچاس پچاس لاکھ روزانہ چھپنے والے اخبارات موجود ہیں.اسی طرح کتابیں چھپتی ہیں تو دس دس بیس بیس لاکھ نسخہ ایک ایک کتاب کا نکل جاتا ہے.یہی خبر اس آیت میں دی گئی تھی کہ صحیفے دنیا میں پھیلا دئے جائیں گے.دوسرے ؔمعنے اس کے یہ تھے کہ صحیفے کھولے جائیں گے یہ پیشگوئی بھی پوری ہو چکی ہے کیونکہ کتابوں کے پڑھنے کا رواج موجود زمانہ میں بہت بڑھ گیا ہے.پھر بڑی بڑی لائبریریاں کھل گئی ہیں جہاں لوگ آتے اور کتابیں وغیرہ پڑھتے رہتے ہیں اور جو لوگ لائبریریوں کے ممبر ہوتے ہیں وہ اپنے گھر پر بھی اُن کتابوں کو پڑھنے کے لئے لے جاتے ہیں.غرض کتابیں بجائے بند رہنے کے کھل گئی ہیں اور علم کا چرچا دنیا میںچاروں طرف ہو گیا ہے.پھر یہ پیشگوئی اس رنگ میں بھی پوری ہوئی ہے کہ بڑی بڑی پُرانی لائبریریاں آثار قدیمہ والوں نے نکال کر رکھ دی ہیں.بختؔ نصر کی لائبریری جو اینٹوں پر لکھی ہوئی تھی وہ سب کی سب نکال لی گئی ہے.اور اس طرح مرُدہ صحیفوں کو بھی زندہ کر دیا گیا ہے.گویا وُہ کتابیں جن کو لوگ بھول چکے تھے اور جو عملی طور پر بالکل متروک ہو چکی تھیں آثار قدیمہ والے
Page 336
ان کو بھی کھود کھود کر نکال رہے ہیں اور لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں.اسی طرح مصر میں فرعون موسیٰ سے پہلے کے آثار نکال کر ان کو پڑھا جا رہا ہے.مصریوںکی پُرانی زبان جو ہیلو گرافی کہلاتی تھی بالکل مٹ گئی تھی.مگر آثار قدیمہ والوں نے اپنی عمریں صرف کر کے آخر اس زبان کا پتہ لگا لیا.چنانچہ وہ ان آثار کو پڑھ کر یہ بتا دیتے ہیں کہ موسیٰ ؑ سے دو ہزار سال پہلے یہ ہوا اور تین ہزار سال پہلے یہ ہوا(The Encyclopedia Britanica Hieroglyphic writing).غرض مُردہ صحیفے اس زمانہ میں زندہ کئے جا رہے ہیں اور اِذَاالصُّحُفُ نُشِرَتْ کی پیشگوئی بڑی صفائی سے پوری ہو رہی ہے.وَ اِذَا السَّمَآءُ كُشِطَتْ۪ۙ۰۰۱۲ اور جب آسمان کی کھال اُتار ی جائے گی.حَلّ لُغَات.کُشِطَتْ کُشِطَتْ کَشَطَ سے مجہول کا مؤنث کا صیغہ ہے اور کَشَطَ کے معنے ہوتے ہیں رَفَعَ شَیْئًا عَنْ شَیْءٍ قَدْ غَشَّاہُ وَنَحَّاہُ.کسی چیز کو دوسری چیز پر سے اٹھانا جس نے اس کو ڈھانکا ہوا ہو.کَشَطَ الْجُلَّ عَنِ الْفَرَسِ وَالْغِطَاءَ عَنِ الشَّیْئِ کے معنے ہوتے ہیں قَلَعَہُ وَنَزَعَہُ وَکَشَفَہُ عَنْہُ یعنی جھول کو گھوڑے پر سے یا کسی اور چیز سے اُتارا یا کسی چیز کو اکھیڑ دیااور کَشَطَ الْبَعِیْرَ کے معنے ہوتے ہیں نَزَعَ جِلْدَہُ.اُس کی جلد کوکھینچ کر اُتارا (اقرب) چنانچہ عربی زبان میں سَلْخُ البَعِیْرِ نہیں کہتے بلکہ کہتے ہیں کَشْطُ الْبَعِیْرِ یعنی سَلَخَ کا لفظ بکری کے متعلق استعمال ہوتا ہے اُونٹ کے متعلق استعمال نہیں ہوتا.پس وَ اِذَا السَّمَآءُ كُشِطَتْ کے معنے ہوں گے جب آسمان کی کھال کھینچی جائے گی (۲)آسمان کا پردہ اُتارا جائے گا.تفسیر.اِذَا السَّمَآءُ كُشِطَتْ میں آسمان سے مراد چونکہ آسمانی علوم بھی لئے جا سکتے ہیں اس لئے اس آیت کے معنے یہ ہوں گے کہ آسمانی علوم پر سے پردے اُٹھا دئے جائیں گے یعنی اُس وقت آسمانی علوم دب گئے ہوں گے اور اُن پر پردے پڑ چکے ہوں گے تب اللہ تعالیٰ ایک ایسے آدمی کو مبعوث کر ے گا جو آسمانی علوم کو کھول کر رکھ دے گا اور قرآن کریم کے وہ اسرار جو چھپے ہوئے تھے یا احادیث کے وہ علوم جو مخفی چلے آتے تھے اُن سب کو ظاہر کر دے گا.دوسرے معنے اس کے یہ ہیں کہ آسمان کی کھال کھینچی جائے گی یعنی علم ہیئت میں حیرت انگیز ترقی ہو گی.ہماری
Page 337
زبان میں بھی کہتے ہیں کہ تم تو بال کی کھال اتارتے ہوجس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم تو بہت باریکیاں نکالتے ہو.چنانچہ اس زمانہ میں علمِ ہیئت میں خیال ووہم سے بھی زیادہ ترقی ہوئی ہے اور سیرِ نجوم اور وسعتِ عالم اور خلقِ عالم اور اجرامِ فلکی وغیر ہ کے بارہ میں غیر معمولی علوم کا اضافہ ہوا ہے جو گزشتہ ہزاروں سال میں بھی نہ ہوا تھا.آج سے سو ڈیڑھ سو سال سےپہلے جو مہندس اور حساب دان تھے وہ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے تھےکہ تھوڑے عرصہ کے بعد ہی کیا سے کیا ہو جائے گا پہلے زمانہ میں زیادہ سے زیادہ دو تین فٹ قطر کی دُوربینیں ہوتی تھیں مگر اب امریکہ میں ایک سو فٹ قطر کی دُوربین ایجاد کی گئی ہے.قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ دُوربین کا جتناقطر بڑھتا جاتا ہے اُتنی ہی اس کی طاقت بڑھتی چلی جاتی ہے کہتے ہیں کہ اِ س دُوربین پر ایک کروڑ ڈالر سے زیادہ خرچ ہوا ہے ہر شخص غور کر سکتا ہے کہ اتنی بڑی دُوربین کتنے سالوں میں تیار ہوئی ہو گی اور اس کے لئے کس قدر ماہرین ساری دنیا سے جمع کئے گئے ہوں گے.بہرحال یہ دُور بین تیار ہوئی اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ علمِ ہیئت میں حیرت انگیز ترقی ہو گئی.دو ستاروں کے باہمی فاصلے کا اندازہ لگانے کے لئے علمِ ہیئت والوں کا طریق یہ ہے کہ وہ رفتارِ نور سے باہمی فاصلے کا اندازہ لگاتے ہیں.وہ کہتے ہیں کہ نور کی رفتار فی سیکنڈ ایک لاکھ چھیاسی ہزار میل ہے ایک لاکھ چھیاسی ہزار کو ساٹھ سے ضرب دیں گے تو ایک منٹ کی رفتار نکل آئے گی پھر ساٹھ سے ضرب دیں گے تو ایک گھنٹہ کی رفتار نکل آئے گی پھراُسے چوبیس سے ضرب دیں تو ایک دن کی رفتار نکل آئے گی اور پھر اُسے تین سو ساٹھ سے ضرب دیں گےتو ایک سال کی رفتار نکل آئے گی.اس بنیاد پر جب وہ ایک ستارے کا دوسرے ستارہ سے فاصلہ بتانا چاہیں تو یہ نہیں کہیں گے کہ وہ ستارہ اتنے میل دُور ہے بلکہ کہیںگے کہ وہ بیس سالِ نوری کے فاصلہ پر ہے یا ایک ہزار سالِ نوری کے فاصلہ پر ہے مطلب یہ کہ ایک سالِ نوری کا جس قدر فاصلہ بنتا ہے اُسے اُتنے سالوں سے ضرب دے لو اور پھر خود ہی اندازہ لگا لو کہ ان میں کتنا فاصلہ ہے.پس دُوربینوں کی ایجاد کے ذریعہ ایک تو سَیر نجوم میں بہت بڑی ترقی ہوئی ہے پھر اس سے وسعتِ عالم کے متعلق سابقہ علوم میں بھی بہت بڑی تبدیلی ہوئی ہے.گزشتہ زمانے کا ذکر تو جانے دو جنگِ عظیم سے پہلے ہئیت دان دو ہزار سالِ نوری عالم کی وسعت سمجھتے تھے مگر پچھلی جنگ کے خاتمہ پر انہوں نے اعلان کیا کہ یہ عالم بارہ ہزار سالِ نوری تک پھیلا ہوا ہے اور اب کہتے ہیں کہ اس عالم میں اتنی وسعت ہے کہ ہم اس کا اندازہ لگانے سے قطعی طور پر قاصر ہیں.اور جو لوگ کچھ اندازے بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ چھتیس یا چالیس ہزارسال نوری تک یہ عالم پھیل گیا ہے.اور اب جب کہ میں اس نوٹ کی نظر ثانی کر رہا ہوں پہلے سے بھی اور فاصلہ کے ستاروں کا پتہ لگنے کا اعلان ہوا ہے.
Page 338
پھر نئے حساب کے ذریعہ انہوں نے اپنی تحقیق میں اس قدر ترقی کر لی ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم نے اس سارے عالم کا مرکز دریافت کر لیا ہے جس میں یہ سورج اور چاند وغیرہ ایسے ہی نظر آتے ہیں جیسے ایک چھوٹا سا ذرہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں اس عالم کے اوپر ایک اَور عالم ہے پھر اَور عالم ہے پھر اور عالم ہے اور آخر میں ایک بہت بڑا مرکز ہے جس کے ارد گرد یہ سب سیّارے اور ستارے اور سورج اور چاند وغیرہ چکّر کھا رہے ہیں.اُن کو اپنی اس تحقیق پر اس قدر ناز ہے کہ ماہرینِ حساب یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے خدائی کا راز دریافت کر لیا ہے گویا وہ مرکز اُن کے نزدیک خدا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہاں سے اللہ تعالیٰ ساری دنیا پر حکومت کر رہا ہے.اسی طرح پیدائشِ عالم کے متعلق پُرانے اور موجودہ نظریہ میں بہت بڑا فرق پیدا ہوگیا ہے اب ایسے آلے نکل آئے ہیں جن سے شعائوں کو پھاڑ کر بتا دیا جاتا ہے کہ وہ شعائیں جن ستاروں سے نکل رہی ہیں اُن میں کون کون سا مادّہ ہے کیونکہ ہر شعاع جو کسی ستارہ سے لوٹتی ہے اس ستارہ کو ساخت دینے والی دھاتوں کا اثر اپنے اندر رکھتی ہے.پہلے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ تمام روشنیاںایک ہی قسم کی ہیں مگر اب ماہرین اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ ہر روشنی الگ قسم کی ہوتی ہے پلاٹینم سے نکلنے والی روشنی کو اگر پھاڑا جائے تو وہ بتا دے گی کہ وہ پلاٹینم میںسے نکلی ہے.اور اگر ریڈیم سے نکلی ہوئی روشنی کو دیکھا جائے تو معلوم ہو جائے گا کہ وہ ریڈیم کی ہے.غرض ہر روشنی کو پھاڑ کر وہ بتا دیتے ہیںکہ اس کے ساتھ کن کن چیزوں کا تعلق ہے.اس علمی ترقی کا یہ فائدہ ہوا ہے کہ سائنس دان یہاں بیٹھے ہوئے سورج کی روشنی لیں گے اور اس کا تجزیہ کر کے بتا دیں گے کہ سورج میں فلاں فلاں عناصر ہیں.مریخ کی روشنی پھاڑ کر بتا دیں گے کہ اس میں فلاں فلاں عناصر ہیں.غرض علمِ ہیئت میں ایسے عظیم الشان تغیّرات ہوئے ہیں کہ اُن کو دیکھ کر حیرت آتی ہے.پھر ایک اور انکشاف بھی ہوا ہے جو اسلام کی بہت بڑی تائید کرتا ہے.پہلے تمام یورپ پر ڈارون تھیوری کا غلبہ تھا.مگر اب کہا جاتا ہے کہ اس دنیا کی کل اڑتالیس ہزار سال عمر ہے اور سورج جوں جوں اپنے مرکز کے قریب آتا جاتا ہے اس کی گرمی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے یہاں تک کہ جب اڑتالیس ہزار سال پورے ہو جائیں گے تو سورج کی گرمی اتنی شدید ہو جائے گی کہ زمین اور اردگرد کے تمام سیّاروں کو پگھلا کر رکھ دے گی.یہ وہی بات ہے جس کا حدیثوں میں ذکر آتا ہے کہ جب قیامت آئے گی تو سورج بالکل قریب آجائے گا اور اُس کی گرمی زمین کو تباہ کر دے گی (ترمذی کتاب صفۃ القیامۃ باب ما جاء فی شان الحساب والقصاص)غرض علمِ ہیئت کے ذریعہ آسمان کی کھال اُدھیڑ دی گئی ہے اور اس علم میں ایسی عظیم الشان ترقی ہوئی ہے کہ جس کی مثال پہلے کسی زمانہ میں نہیں ملتی.آسمانی کتب کی تحقیقات تیسرےؔ معنے اس کے یہ ہیں کہ سماء سے مراد سماوی علوم لئے جائیں.اس صورت
Page 339
میں اس آیت کا یہ مطلب ہو گا کہ یہ لوگ دین کو پھاڑ کر رکھ دیں گے اور اُس کی ایسی چھان بین کریں گے کہ اپنے خیال میں اس کی کھال اُدھیڑ دیں گے.چنانچہ دیکھ لو اس زمانہ میں دین کے متعلق ایسی ایسی بحثیں ہوئی ہیں جو پہلے کبھی نہیں ہوئی تھیں.پھر ہر مذہب والے نے اپنے اپنے مذہب کا ایسا تجزیہ کیا ہے کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں رہی.مثلاً بائیبل ہے عیسائیوں نے اس کی کھال اُدھیڑ کر رکھ دی ہے اور ثابت کیا ہے کہ فلاں بات موسیٰ ؑ کی نہیں بلکہ ہارونؑ کی ہے.یا یہ لفظ فلاں زبان کا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں فلاں ز بان تھی اس لئے معلوم ہوا کہ یہ لفظ بعد میں ملایا گیا ہے.غرض ایسا تجزیہ کیا ہے کہ ایک ایک بات کو خود عیسائیوں نے کھول کر رکھ دیا ہے.اس چیر پھاڑ میں اگر کوئی زندہ وجود بچا ہے تو وہ صرف قرآن ہے.ویدوں کے متعلق بھی خود ہندو محققین نے بہت بڑی تحقیقاتیں کی ہیں اور انہوں نے ثابت کیا ہے کہ ویدوں میں فلاں فلاں زبان شامل ہے اور یہ زبان فلاں فلاں سنہ میں بولی جاتی تھی.اسی طرح ویدوں کی تاریخ اور اُن کی ترتیب کے متعلق ایسا تجزیہ کیا ہے کہ اُن کی کھال اُدھیڑ دی ہے.اس چیر پھاڑ سے صرف قرآن ہی محفوظ رہا ہے اور کوئی کتاب محفوظ نہیں رہی.مگر چونکہ پیشگوئی تھی کہ بہرحال آسمانی علوم کی کھال اُتاری جائے گی اور اُن کے اسرار کو منکشف کیا جائے گا اس لئے اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کاملہ کے ماتحت اور کتابوں کی چیر پھاڑ کا کام تویورپ والوں کے سپرد کر دیا اور قرآنی علوم کے انکشاف کا کام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ و السَّلام کے سپرد کر دیا.کیونکہ وَ اِذَا السَّمَآءُ كُشِطَتْ کی پیشگوئی نے سب پر چسپاں ہونا تھا مگر باقی کتب کا چونکہ اعزاز مدنظر نہیں تھا اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کو قصابوں کے سپرد کر دیا کہ تم اُن کی کھالیں اُدھیڑو.اور قرآن کا چونکہ اعزاز مدنظر تھا اس لئے اُسے بجائے غیروں کے ہاتھوں میں دینے کے اپنے ایک برگزیدہ کے ہاتھ میں دے دیا کہ تم اس کے معارف ظاہر کرو اور اس کے حقائق دنیا پرروشن کرو.وَ اِذَا الْجَحِيْمُ سُعِّرَتْ۪ۙ۰۰۱۳ اور جب جہنم کو بھڑکا یا جائے گا.حَلّ لُغَات.سُعِّرَتْ سُعِّرَتْ سَعَّرَ سے مجہول کا مؤنث کا صیغہ ہے.اور سَعَّرَ النَّارَ وَالْحَـرْبَ کے معنے ہوتے ہیں اَوْ قَدَ ھُمَا وَاَشْعَلَھُمَا وَھَیَّجَھُمَا کہ جنگ کو یا آگ کو بھڑکایا (اقرب) پس اِذَا الْجَحِيْمُ سُعِّرَتْ کے معنے ہوں گے جب جہنم کو بھڑکایا جائے گا.
Page 340
تفسیر.جَھَنَّمَ کے معنے خود آگ کے ہیں.پس جو پہلے ہی آگ ہے اس کا بھڑکایا جانا اور بھی خطرناک حالت پر دلالت کرتا ہے یہ ایسی ہی بات ہے جیسے کہتے ہیں ’’کریلہ اور پھر نیم چڑھا‘‘.جہنم کے بھڑکائے جانے کے ایک معنے تویہ ہیں کہ اُ س زمانہ میں گناہ کی زیادتی ہو جائے گی کیونکہ جب کوئی مہمان آیا ہوا ہو تو اس کا کھانا پکانے اور ضیافت کرنے کے لئے آگ کو بھڑکایا جاتا ہے.پس جہنم جن لوگوں کا گھر ہے اور جن کا نُزل واقعہ ہوا ہے جب وہ کثرت سے اُس گھر میں جائیں گے تو یہ لازمی بات ہے کہ اُس کی آگ بھی بھڑکائی جائے گی.پس اس کے ایک معنے یہ ہیں کہ گناہوں کی زیادتی کی وجہ سے اُس زمانہ میں دوزخیوں کی تعداد بڑھ جائے گی.اِذَا الْجَحِيْمُ سُعِّرَتْ میں نبی کے آنے کی پیشگوئی وَاِذَا الْجَحِيْمُ سُعِّرَتْکے ایک معنے یہ بھی ہیں کہ اُس وقت خدا تعالیٰ کا ایک نبی آئے گا جس کی مخالفت کی وجہ سے خدا تعالیٰ کا غضب بھڑک اُٹھے گا کیونکہ خدا تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَ مَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلًا (بنی اسرائیل:۱۶)ہم اُس وقت تک لوگوں پر عذاب نازل نہیں کرتے جب تک اپنا رسول بھیج کر اُن پر حجت تمام نہ کر لیں.پس اس آیت میں ایک لطیف اشارہ اس امر کی طرف بھی ہے کہ اُس وقت خدا تعالیٰ کا ایک مامور آئے گا کیونکہ جب اس کی طرف سےکوئی مامور آتا ہے تو اس کے آنے کے ساتھ جہاں مومنوں کے لئے رحمت کے دروازے کھلتے ہیں وہاں کفار کے لئے عذاب کے دروازے بھی کھول دئے جاتے ہیں.وَ اِذَا الْجَنَّةُ اُزْلِفَتْ۪ۙ۰۰۱۴ اور جب جنت کو قریب کر دیا جائے گا.حَلّ لُغَات.اُذْلِفْتَ اُذْلِفْتَ اَ زْلَفَ سے مجہول کا مؤنث کا صیغہ ہے اور اَ زْلَفَ کے معنے ہیں قَرَّبَہُ اُس کو قریب کیا (اقرب) پس وَاِذَاالْجَنَّۃُ اُزْلِفَتْ کے معنے ہوں گے جب جنت قریب کی جائے گی.تفسیر.یہ اِذَا الْجَحِيْمُ سُعِّرَتْ کا ایک طبعی نتیجہ ہے جو بیان کیا گیا ہے کیونکہ جب گناہ بڑھ جاتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں رہتی تو اُس وقت جنت بھی لوگوں کے قریب کر دی جاتی ہے اور تھوڑی سی محنت اور تھوڑی سی قربانی سے وہ اُس کو حاصل کرلیتے ہیں.جس زمانہ میںنیکی کی کثرت ہو جنت کا حصول اتنا آسان نہیں ہوتا جتنا اُس زمانہ میں جب لوگوں میں عام طور پر بے دینی پائی جاتی ہو.کیونکہ اُس وقت خدا تعالیٰ کی طرف ادنیٰ
Page 341
توجہ بھی اُس کی خوشنودی کا مستحق بنا دیتی ہے.اِذَا الْجَنَّةُ اُزْلِفَتْ کے دو معنے اس آیت کے ایک یہ معنے بھی ہو سکتے ہیں کہ جنت کے حصول کے لئے اس زمانہ کی قربانیاں نسبتاً آسان ہوں گی جہاد بند ہو گااور اس طرح جانی قربانی کے مواقع پیش نہیں آئیںگے صرف مالی قربانی کر کے یا وقت کی قربانی کر کے یا جذ بات و احساسات کی قربانی کر کے وہ جنت کو حاصل کر سکیںگے پہلا زمانہ وہ تھا جب اَلْجَنَّۃُ تَحْتَ ظِلَالِ السُّیُوْفِ (بخاری کتاب الجہادباب الجنة تحت بارقة السیوف) کا سبق مومنوں کے سامنے دُہرایا جاتا تھا مگر اِس زمانہ میں تلوار کا جہاد اللہ تعالیٰ کی حکمت کے ماتحت بند ہے اس لئے اب وہ تکالیف برداشت نہیں کرنی پڑتیں جو پہلے زمانوں میں برداشت کرنی پڑتی تھیں اب جہاد بالسیف کے بغیر ہی مالی قربانیوں میں حصہ لے کر جنت مل سکتی ہے.اس آیت کے ایک معنے یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ مامور من اللہ کی بیعت کی وجہ سے جنت کا پانا اُن سے پہلے لوگوں کی نسبت آسان ہو جائے گا جنہوں نے کسی مامور کا زمانہ نہیں دیکھا.آج سے سوسال پہلے ساری عمر بزرگانِ دین کی صحبت میں گزار کر جو نور حاصل ہوتا تھا وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ایک نکتۂ معرفت سے انسانی قلب میں پیدا ہو جاتا ہے پھر جو نشانات اور معجزات اس وقت ہمارے سامنے ہیں اور جن کے ذریعہ ایک زندہ خدا ہمیںنظر آرہا ہے یہ پہلے کہاں تھے.اسی طرح اللہ تعالیٰ کے تازہ الہامات ہمارے ایمانوں میں جو تازگی پیدا کرتے ہیں وہ پہلے لوگوں کو کہاں نصیب ہوتی تھی.پس حق یہی ہے کہ اس زمانہ میں ایک مامور من اللہ کی بعثت اور پھر اُس کی بیعت کی وجہ سے جنت کا حصول پہلے لوگوں کی نسبت بہت زیادہ آسان ہو گیا ہے اور یہی مامور کے زمانہ کی علامت ہوتی ہے کہ اُس وقت جنت بالکل قریب کر دی جاتی ہے.عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّاۤ اَحْضَرَتْؕ۰۰۱۵ (اُس دن) ہر جان جو کچھ اُس نے حاضر کیا ہے جان لے گی.تفسیر.عَلِمَتْ نَفْسٌ سے خدا کی تقدیر خاص کا اجراء فرماتا ہے اُس دن الٰہی تقدیر خاص طور پر جاری ہو گی اور نتائج اعمال خاص طور پر نکلنے شروع ہوں گے مطلب یہ کہ عام زمانہ میں فردی محاسبہ ہوتا ہے لیکن انبیاء کے زمانہ میں قومی محاسبہ ہوتا ہےجیسا کہ آیت وَ مَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلًا (بنی اسرائیل :۱۶)سے ظاہر ہے اور قومی محاسبہ بڑا سخت ہوتا ہے فردی محاسبہ نظر نہیں آتا کیونکہ اس کا تعلق انفرادی طور پر الگ الگ لوگوں
Page 342
سے ہوتا ہے لیکن قومی محاسبہ ایسی چیز ہے جو سب کو نظر آجاتی ہے کیونکہ اس کا تعلق تمام قوم کے ساتھ ہوتا ہے چنانچہ زلازل اور جنگوں کی کثرت سے اس قومی محاسبہ کے دن کا اب اظہار ہو رہا ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زلازل سے زمین اس طرح ہلائی جائے گی کہ انسان پکار اٹھے گا مَالَھَا (سورۂ زلزال) زمین کو کیا ہو گیا ہے کہ عذاب پر عذاب اور تباہی پر تباہی آتی جا رہی ہے.چنانچہ اب عام طور پر یہی احساس لوگوں کے قلوب میں پیدا ہو رہا ہے کہ یہ خدائی عذاب ہے جو دنیا پر مسلّط ہے اور اسی کی طرف سے اِن زلازل اور جنگوں اور وبائوں کے ذریعہ دنیا میں تغیر پیدا کیا جا رہا ہے پس فرماتا ہے ایک دن آئے گا جب اِن زلازل اور جنگوں کے نتائج قومی طور پر نکلنے شروع ہو جائیں گے.اور تقدیر الٰہی دنیا میں خاص طور پر جاری ہو جائے گی.فَلَاۤ اُقْسِمُ بِالْخُنَّسِۙ۰۰۱۶ پس ایسا نہیں (جو تم خیال کرتے ہو) میں شہادت کے طور پر پیش کرتا ہوں.الْجَوَارِ الْكُنَّسِۙ۰۰۱۷ چلتے چلتے پیچھے ہٹ جانے والوں کو (جو ساتھ ہی) ناک کی سیدھ چلنے والے (بھی ہیں اور پھر) گھروں میں بیٹھے رہنے والے بھی.حَلّ لُغَات.اَلْخُنَّسُ اَلْخُنَّسُ خَانِسٌ کی جمع ہے جو خَنَسَ سے اسم فاعل ہے.اور خَنَسَ عَنْہُ کے معنے ہوتے ہیں تَاَخَّرَ وَانْقَبَضَ.اس سے پیچھے ہٹ گیا.اور خَنَسَ بَیْنَ اَصْحَابِہٖ کے معنی ہوتے ہیں اِسْتَخْفٰی اپنے ساتھیوں میں چھپ گیا.اور جب خَنَسَ الْقَوْلَ کہیں تو معنے ہوتے ہیں اَسَائَ ہٗ.اسے بُری بات سے مخاطب کیا (اقرب) گویا خَانِسٌ کے معنے ہوئے جو پیچھے ہٹ جاتا ہے یا مخفی ہو جاتا ہے.یا بُری باتیں کہنے لگ جاتا ہے تو خُنَّس ہوئے بُری بات کہنے والے.پیچھے ہٹ جانے والے چھپ جانے والے.اَلْجَوَارِ اَلْجَوَار اَلْجَارِیَۃُ کی جمع ہے.جو اَلْجَارِی سے مؤنث کا صیغہ ہے.اور جَارِیَۃ چلنے والی کو کہتے ہیں.نیز اس کے معنی ہیں (۱) اَلصَّبِیَّۃُ بچہ (۲) اَلْاَمَۃُ لونڈی (منجد) (۳) اَلشَّمْسُ سورج (۴)اَلسَّفِیْنَۃُ کشتی (۵)اَلْحَیَّۃُ.اور سانپ کو بھی کہتے ہیں.(اقرب) پس جَوَارٍ سے مراد لونڈیاں بھی ہو سکتی ہیں.لڑکیاں بھی ہو سکتی ہیں.سورج بھی ہو سکتا ہے.کشتیاں بھی ہو سکتی ہیں.سانپ بھی ہو سکتا ہے اور پھر سیدھے چلنے والے وجود بھی اس
Page 343
سے مراد ہو سکتے ہیں.اَلْکُنَّسُ اَلْکُنَّسُ اَلْکَانِسُ کی جمع ہے اور اَلْکَانِسُ اُس ہرن کو کہتے ہیں.جو اپنی غار میں داخل ہو جاتا ہے.(اقرب) کیونکہ کناس ہرن کی رہائش کی جگہ کو کہتے ہیں.تفسیر.فَلَاۤ اُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ.الْجَوَارِ الْكُنَّسِ میں مسلمانوں کے اندر آخری زمانہ میں تین صفات پیدا ہو جانے کی پیشگوئی فَلَاۤ اُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ.الْجَوَارِ الْكُنَّسِ اس میں گواہ کے طور پر ان ہستیوں کو پیش کیا گیا ہے جن کی تین صفات ہیں.وہ خُنسؔ ہیںیعنی پیچھے ہٹ جاتی ہیں.آگے کو چلتی ہیں.اور چھپ جاتی ہیں.ان صفات والی ہستیوں سے مراد اس زمانہ کے مسلمان ہیں.یہ تین صفات وُہ ہیں جو قوم کی تباہی کا مؤجب ہوتی ہیں.(۱)خطرہ کے وقت پیچھے ہٹ جانا (۲)بلا غور وفکر آگے بڑھتے چلے جانا (۳)سب کام چھوڑ چھاڑ کر گھروں میں نکمّے بیٹھ جانا.چونکہ پہلی آیت میں عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا اَحْضَرَتْ فرمایا تھا.یعنی انسان نے جو کچھ کیا ہے اس کا نتیجہ ضروردیکھ لے گا.اس کے اس زمانہ کے اعمال کو بتاتا ہے.کہ وہ اس وقت تین پہلو رکھتے ہوں گے.یعنی اوّل مسلمان مغربیت سے ڈر کر میدان سے بھاگ جائیں گے.اور غلط راستہ اختیار کر لیں گے.پھر اس کے ساتھ ہی عقل و دانش کو ترک کر کے رسمی اسلام کو بھی پیش کرتے رہیں گے.لیکن باوجوداس کے حقیقی قربانی ان سے مفقود ہو گی.وہ چھپ کر گھروں میں بیٹھ جائیں گے.اور دشمن کا روحانی مقابلہ نہ کریں گے.بھلے بُرے سے کچھ تعلق نہ رکھیں گے.اس وجہ سے اسلام کمزور ہو جائے گا.اور دشمنانِ اسلام غالب آتے چلے جائیں گے.ادنیٰ تدبر سے معلوم ہو سکتا ہے کہ اس زمانہ میں مسلمانوں کی حالت ایسی ہی ہے اور یہی زمانہ اس سورۃ میں مذکور ہے.اوّل تو سب کے سب مسلمان خُنّس ہیں یعنی سیدھے راستہ سے بھٹک گئے ہیں.اور نقطہء صداقت سے واپس ہٹ گئے ہیںیعنی انہوں نے کفر کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر کام کرنا شروع کر دیا ہے.اور اسی طریق کو وہ خدمت قوم و خدمت ملک سمجھتے ہیں.یورپ کے طریق اور یورپ کے رویہ کو اور اس کے فلسفہ کو ان لوگوں نے اپنا راہ نما بنا لیا ہے اور اس کےخلاف کو موجب خسران وتباب سمجھتے ہیں.درحقیقت وُہ نام کے مسلمان ہیں اور انہوں نے مغربیت کا نام اسلام رکھ لیا ہے.اب یہ حال ہے کہ ایک ہی طور و طریق رکھ کر ایک آدمی عیسائی کہلاتا ہے اور ویسا ہی طور و طریق رکھ کر دوسرا آدمی مسلمان کہلاتا ہے.محقّق دیکھ کر حیران ہوتا ہے.کہ یہ کیا عجیب بات ہے کہ وہی طور و طریق مسیحیت بھی کہلاتا ہے.اور اسلام بھی.لیکن اس کے ساتھ ہی ان کی یہ حالت ہے کہ جہاں وہ حقیقت میں اسلام سے ہٹ گئے ہیں.ظاہر میں وہ اُسی راستہ پر چلے جا رہے ہیں.اور کہلاتے مسلمان ہی ہیں.گویا ایک طرف اسلام کو چھوڑ رہے ہیں.اور
Page 344
دوسری طرف اسلام کی طرف رغبت بھی ظاہر کر رہے ہیں.اور یہ دکھاتے ہیں کہ وہ اسلامی راستہ پر چل رہے ہیں.لیکن ان کا یہ جوش وخروش صرف رسمی اور زبانی ہے.کیونکہ جہاں ایک رسمی اسلام کی اتباع کا ان کو دعویٰ ہے.وہاں یہ بھی نظر آتا ہے کہ کام کے وقت وہ اپنے گھروں میں چھپ جاتے ہیں.اور اسلام کی خاطر کوئی قُربانی نہیں کرتے.یہ نقشہ لفظًا لفظًا اس وقت کے مسلمانوں پر چسپاں ہوتا ہے.وہ اسلام کی تعلیم کو چھوڑ چکے ہیں.مگر باوجود اس کے اسلام پر چلنے کے دعویدار بھی ہیں.اوراس کی تائید میں خوب نعرے بھی لگاتے ہیں.لیکن عملًا وہ ہر سچی قربانی سے گریز بھی کر رہے ہیں.اس گری ہوئی حالت میں بھی اگر مسلمان سچی قربانی کریں جس طرح یورپ کے لوگ کرتے ہیں.تو وہ اپنی دنیوی عزت کا کثیر حصہ واپس لے سکتے ہیں.مگر حقیقی عمل کے وقت وُہ کُنّس ہو جاتے ہیں.یعنی اپنی غاروں میں چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں.اور دشمن اسلام کی متاع لوٹ کر لے جاتا ہے.یورپ تو الگ رہا ہندوستان کی غلام اقوام کے مقابلہ پر بھی مسلمان باوجودبعض قوموں سے زیادہ ہونے کے ان کے مقابلہ پر دلیری سے نہیں کھڑا ہو سکتا.کیونکہ دائمی اور مستقل قربانی سے وہ گھبراتا ہے.اس لئے پہلی بھبکی کے بعد وہ پیٹھ دکھا کر بھاگ جاتا ہے.اور میدان ہمیشہ اس سے کمزور لیکن زیادہ منظم جماعت کے ہاتھ میں آجاتا ہے.وَ الَّيْلِ اِذَا عَسْعَسَۙ۰۰۱۸وَ الصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَۙ۰۰۱۹ اور رات کو (شہادت کے طور پر پیش کرتا ہوں) جب وہ خاتمہ کو پہنچ جاتی ہے.اور صبح کو جب وہ سانس لینے لگتی ہے.حَلّ لُغَات.عَسْعَسَ عَسْعَسَ الَّیْلُ کے معنے ہیں مَضٰی رات گزر گئی.چل گئی.نیز اس کے معنے ہیں اَظْلَمَ.رات کی تاریکی پورے زور سے چھا گئی.(اقرب) تَنَفَّسَ تَنَفَّسَ کے اصل معنے ہیں اَدْخَلَ النَّفْسَ اِلٰی رِئَتِہٖ کہ سانس کو پھیپھڑوں میں داخل کیا.یعنی سانس لیا.اور جب تَنَفَّسَ الصُّبْحُ کہیں تو معنی ہوتے ہیں تَبَلَّجَ صبح روشن ہو گئی.(اقرب) تفسیر.پہلی آیت میں جو بھیانک نقشہ اس زمانہ کے مسلمانوں کا کھینچا گیا تھا.اور جسے دیکھ کر تباہی کے سوا کوئی انجام نظر نہ آتا تھا.اب ان آیات میں تسلی دلاتا ہے اور فرماتا ہے کہ تاریکی کا یہ دور دائمی نہ ہو گا.بلکہ اللہ تعالیٰ رات کو بھی بطور شہادت پیش کرتا ہے.جب وُہ چلی جائے گی.اور خاتمہ کے قریب پہنچ جائے گی.اور صبح کو بھی بطور شہادت پیش کرتا ہے.جب وہ سانس لے گی.یعنی اپنے وجود کو ظاہر کرنے لگے گی.رات کا جانا اور صبح کا
Page 345
آنا تنزّل کے دَور کے خاتمہ اور ترقی کے نئے دَور کے ظہور پر دلالت کرتا ہے.اور اسی طرف اس آیت میںاشارہ ہے.اسلام کے اس دَور تنزل پر اللہ تعالیٰ خاموش نہ رہے گا.بلکہ اسے دُور کرنے کے سامان پیدا کرے گا.اور اس وقت صبح کا ستارہ اس کی طرف سے طلوع ہو گا.یعنی وقت کا مصلح اور امام جو ہر تاریک رات کے بعد صبح کے ستارہ کی طرح ظاہر ہوتا ہے.اس وقت ظاہر ہو گا.جب ظلمت بڑھتی چلی جاتی ہے.اور انسان روشنی کے ظہور سے مایوس ہو جاتا ہے.اس وقت اگر روشنی کے ہلکے سے آثار نمودار ہوں تو وہ نظارہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسے ایک انسان بظاہر مرا ہوا نظر آتا ہے.لیکن دراصل ابھی زندہ ہوتا ہے.اس وقت جب اس کے مونہہ پر پانی کے چھینٹے دئے جاتے ہیں تو گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ کی جدوجہد کے بعد وہ ایک ہلکی سی سُبکی لیتا ہے جس پر گھر والے خُوش ہو جاتے ہیں کہ یہ مرا نہیں بلکہ زندہ ہے.تَنَفَّسَ الصُّبْحُ میں اسلام کی نازک حالت کا نقشہ اسی طرح فرماتا ہے وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ.اس وقت ایسا تاریکی کا زمانہ ہو گا کہ ہر شخص کہے گا اسلام اب مر چکا.اس کی زندگی کے کوئی آثار باقی نہیں رہے.کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اسلام کےمردہ کوچھوڑ کر چلے جائیں گے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بیٹھ کر رونے لگ جائیں گے.مگر کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے کام میں لگے رہیں گے اور وُہ اس کے مونہہ پر چھینٹے دیتے چلے جائیں گے.یہاں تک اسلام ذرا سا سانس لے گا.اس وقت سب کہیں گے کہ لو اسلام زندہ ہو گیا.پس فرماتا ہے وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ ہم شہادت کے طور پر صبح کو پیش کرتے ہیں جب وہ کوشش سے ایک سانس لے گی.تَنَفَّسَ الصُّبْحُ کے معنے ہوتے تَبَلَّجَ اَیْ اَشْرَقَ وَاَنَارَ یعنی روشن ہو گئی یا اس نے روشن کر دیا.اس مفہوم کو اور طرح بھی ادا کیا جا سکتا تھا.مگر اللہ تعالیٰ نے الفاظ ایسے رکھے ہیں جو مایوسی کی حالت سے تعلق رکھتے ہیں.اور بتاتے ہیں کہ اسلام کی ترقی اس وقت ناممکن خیال کی جاتی ہو گی.بہرحال فرماتا ہے وقت آئے گا جب رات دُور ہو جائے گی.اور صبح کوشش سے ایک سانس لے گی جس پر مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو جائیں گے.اور ان کے دلوں میں یہ یقین پیدا ہو جائے گاکہ اسلام اب ضرور غالب آکر رہے گا اور خدام اسلام جیت جائیں گے.
Page 346
اِنَّهٗ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍۙ۰۰۱۹ذِيْ قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ یقیناً وہ ایک بزرگ رسول کا کلام ہے.(جو) قوت والا اور صاحب عرش کے حضور بڑا درجہ رکھنے والا (ہے) مَكِيْنٍۙ۰۰۲۰مُّطَاعٍ ثَمَّ اَمِيْنٍؕ۰۰۲۱ (جو) مطاع (بھی) ہے (اور) اس کے ساتھ امین بھی.حَلّ لُغَات.مَکِیْنٌ مَکِیْنٌ مَکُنَ سے ہے.اور مَکُنَ فُلَانٌ عِنْدَ السُّلْطَان کے معنے ہوتے ہیں عَظُمَ عِنْدَہُ وَارْتَفَعَ وَصَارَذَا مَنْزِلَۃٍ کہ فلاں شخص کا رتبہ بادشاہ کے ہاں بڑھ گیا.اور بادشاہ کے حضور مقرب اور معزز ہو گیا (اقرب) پس مَکِیْنٌ کے معنے ہوں گے بادشاہ کے ہاں معزز مقرب اور رتبہ رکھنے والا.تفسیر.آخری زمانہ میں اسلام کی ترقی کی پیشگوئی پر تین اعتراضات اور ان کے جوابات اسلام کی ترقی اور اس کے تنزل کے متعلق اور آخر میںا سلام کے دوبارہ غلبہ اور عروج کے متعلق ان آیات میں جس تفصیل سے روشنی ڈالی گئی ہے.اس کو دیکھ کر ایسے شخص کے دل میں جس کے سامنے ابھی ان واقعات میں سے کوئی واقعہ بھی رُونما نہیں ہوا تھا تین اعتراض پیدا ہوتے تھے.اول یہ کہ آپ اسلام کے تنزل کی خبر دے رہے ہیں.حالانکہ اس تنزل کی خبر کے معنی ہی کیا ہیں.اسلام کی تو دنیا میں کہیں بھی ترقی نظر نہیں آتی.اور جب آپ کے مذہب کا دنیا میں کہیں نام ہی نہیںاور نہ لوگ کثرت سے اس میں شامل ہیں تو اس کے تنزل کی خبر دینے کے کیا معنی ہیں.(۲)پھر جب اسلام ترقی کر گیا اور مسلمانوں کو حکومتیں حاصل ہو گئیں.اس وقت اگر ان سے کوئی پوچھتا کہ کیا تمہارابھی کبھی تنزل ہو گا.تو وہ سب اس کو ناممکن بتاتے.اور کہتے کہ اسلام کی شان وشوکت کو کون توڑ سکتا ہے.بنو امیہ اور بنو عباس کے کیا وہم وگمان میں بھی یہ بات آسکتی تھی کہ وُہ عیسائی جو ان کی ماتحتی میں اپنی زندگی کے دن بسر کر تےتھے کسی دن غالب آجائیں گے اور اس قدر طاقت حاصل کر لیں گے کہ مسلمان اگر سارے مل کر بھی شور مچائیں گے تو وُہ اُس آواز کو نہیں سُنیں گے.گویا جس طرح ابتدا ء اسلام میں لوگوں کے لئے یہ بات ماننی ناممکن تھی کہ اسلام کسی زمانہ میں ترقی کر جائے گا.اسی طرح اسلام کے دَور ترقی میں لوگوں کے لئے یہ بات ماننی مشکل تھی کہ اسلام کسی وقت گر جائے گا (۳)پھر جب اسلام کا تنزّل ہوا تو ایسا ہوا کہ اب مسلمانوں کو لاکھ سمجھائو کہ وُہ پھر ترقی کر جائیں گے ان کی سمجھ میں ہی یہ بات نہیں آتی کہ اتنے عظیم الشان تنزل کے بعد وُہ کس طرح ترقی کر سکیں گے.
Page 347
حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃوالسلام پر ایمان لانے کے بعد یہ یقین پیدا ہوتا ہے کہ اسلام غالب آئے گا.لیکن اگر آپ سے تعلق نہ ہو تو اس یقین کے پیدا ہونے کا کوئی ذریعہ ہی نظر نہیں آتا.یہی وجہ ہے کہ مسلمان جب بھی اپنے غلبہ کے لئے کوشش کرتے ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ عیسائیوں سے صلح ہو جائے.یا ہندوئوں سے مل کر ان کو حکومت حاصل ہو جائے.ان کے وہم وگمان میں بھی یہ بات کبھی نہیں آتی.کہ جو آج اسلام کا حال ہے وہی حال اب عیسائیت کا ہونے والا ہے اور جس طرح آج مسلمان عیسائیوں کے مقابلہ میں بالکل بے بس ہیں اسی طرح عیسائی مسلمانوں کے سامنے بے حیثیت ہو جائیں گے یہ پروگرام صرف ہماری جماعت کا ہی ہے کیونکہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے نشانات کو اپنی آنکھوں سے پورا ہوتے دیکھا.اور ہم ایک ایسے خدا پر ایمان لائے ہیں جو زندہ اور طاقتور خدا ہے.غرض ہر قدم پر دوسرے قدم کا وہم بھی نہیں آسکتا تھا.جب یہ سورۃ نازل ہوئی اس وقت اسلام کی ترقی کا خیال ناممکن تھا.جب اسلام کی ترقی کا دَور آیاتو اس کے تنزل کاخیال ناممکن تھا.اور جب اس پر تنزل آیاتو اب اس کی ترقی کو ناممکن بتایا جا رہا ہے.اور چونکہ اس پیشگوئی کا ہر قدم ایسا تھا جس پر لوگوں کو یقین ہی نہیں آسکتا تھا اس لئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّہُ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ کَرِیْمٍ.تم قدم بقدم چلو.اور پھر دیکھو کہ ہمارے رسول کی باتیں کس طرح پوری ہوتی ہیں آج تم ہمارے رسول کو تحقیر کی نگاہوں سے دیکھتے ہو.لیکن ہم تمہارے سامنے اس پیشگوئی کا اعلان کرتے ہیں کہ پہلا قدم یہ ہوگا کہ یہ رسول کریم تسلیم کیا جائے گا.یہ ایک قریب کی پیشگوئی ہے جس کے پورا ہونے پر بعید زمانہ سے تعلق رکھنے والی پیشگوئیوں کے بھی پُورا ہونے کی بھی امید کی جا سکتی ہے.اِس وقت یہ تمہیں غیر معزز نظر آرہا ہے اور تم اسے اپنے رحم پر سمجھتے ہولیکن عنقریب تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے کہ اس کا رسول کریم ہونا ثابت ہو جائے گا.ا ور جب یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ اگر ایک ناممکن بات ہو گئی ہے تو دوسری ناممکن باتیں بھی وقوع میں آجائیں گی.یہاں جو یہ فرمایا گیا ہے کہ اِنَّہُ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ کَرِیْمٍ اس پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اس سے یہ نیجہ نکلتا ہے قرآن خدا کا کلام نہیں بلکہ بندے کا کلام ہے.مگر یہ اعتراض کلام کے طریق کو نہ سمجھنے کے نتیجہ میں پیدا ہو اہے جب کوئی شخص ہم سے آکر بات کرتا ہے تو ہماری اس سے دو بحثیں ہوتی ہیں.اول یہ کہ وہ جو کچھ کہتا ہے آیا لفظاً لفظاً درست ہے یا نہیں.دوم بعض دفعہ الفاظ کا سوال نہیں ہوتا.صرف اتنا دریافت کیا جاتا ہے کہ آیا اس نے پیغام کا مفہوم درست طورپر ادا کیا ہے یا نہیں.یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں.اور ان کے الگ الگ ہونے کی وجہ سے دونوں کا آپس میں فرق بھی بہت بڑا ہے.مثلاً ایک شخص ہمارے پاس آکر کہتا ہے کہ مجھے فلاں شخص نے بتایا ہے کہ تم کو
Page 348
فلاں عہدہ دے دیا گیا ہے.اب کبھی تو اس شخص کو خود بھی معلوم ہوتا ہے کہ مجھے فلاں عہدہ دے دیا گیا ہے.مگر اس کے آرڈر کے الفاظ کا علم نہیں ہوتا.ایسی حالت میں وہ خبر دینے والے سے پوچھتا ہے کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ آرڈر کے الفاظ کیا تھے.اگر اسے علم ہو تو بتا دیتا ہے.اور اگر علم نہ ہو تو معذرت کر دیتا ہے.لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اسے پہلی دفعہ نئے عہدہ کی خبر ملتی ہے ایسی حالت میں وہ یہ دریافت کرتا ہے کہ بتاؤ تم نے جو مجھے پیغام آکردیا ہےآیا یہ اپنے مفہوم کے لحاظ سے درست ہے ؟اس وقت اسے الفاظ سے اتنی غرض نہیں ہوتی.جتنی مفہوم کے درست ہونے سے غرض ہوتی ہے.تو یہ الگ الگ صورتیں ہیں جو عام طور پر پیش آتی رہتی ہیں.اب ہمیں غور کر نا چاہیے کہ دشمن کا مطالبہ کیا تھا جس کے متعلق اِنَّهٗ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ کہا گیا.سو اگر کوئی شخص غور کرے تو ادنیٰ فکر سے بھی یہ بات معلوم کر سکتا ہے کہ دشمن کا سوال یہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نےاِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ کہا ہے یا نہیںیا اِذَا النُّجُوْمُ انْكَدَرَتْاس نے کہا ہے یا نہیں.بلکہ دشمن تو یہ پوچھتا تھا کہ الفاظ چاہے کچھ ہوں سوال یہ ہے کہ ان کا جو مفہوم ہے وہ کب پورا ہوگا.اسے اِذَایا اَلشَّمْسُ یاكُوِّرَتْ یا اَلنُّجُوْمُ وغیرہ الفاظ سے کوئی بحث نہیں تھی.وہ کہتا تھا کہ الفاظ خواہ کچھ رکھ لو.سوال یہ ہے کہ یہ باتیں کب ہوں گی؟اِنَّهٗ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ کَرِیْمٍ میں اس سورۃ کے الفاظ کی طرف اشارہ نہیں.بلکہ اس کے مفہوم کی طرف اشارہ ہے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ دشمن کی طرف سے الفاظ کے متعلق بھی بحث کی جاتی ہے مگر جہاں پیشگوئیوں کے متعلق بحث ہو وہاں یہ بحث نہیں ہوتی کہ الفاظ کون سے نازل ہوئے ہیں بلکہ وہاں یہ بحث ہوتی ہے کہ ان الفاظ کا مفہوم کب پورا ہو گا اللہ تعالیٰ دشمنوں کے اس مطالبہ کا جواب دیتے ہوئے فرماتا ہے اِنَّہُ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ کَرِیْمٍ یہ بات جو کہی گئی ہے ایک معزز رسول نے کہی ہے.اور معزز رسول جھوٹ نہیں بولا کرتا.اس لئے یہ مفہوم ایک دن پورا ہو کر رہے گا.پس یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ اس جگہ کفار کی طرف سے الفاظ کے متعلق اعتراض نہیں کہ آیا وہ خدا کی طرف سے ہیں یا نہیں.بلکہ مفہوم کے متعلق اعتراض ہے.اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّہُ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ کَرِیْمٍ یہ پیغام جو تم کو دیا گیا ہے ایک رسول کریم نے دیا ہے.اِس جگہ اللہ تعالیٰ نے رسول امین نہیں کہا بلکہ رسول کریم کہا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں الفاظ کے ضبط کی بحث ہوتی ہے وہاں رسول امین کے الفاظ استعمال کئے جاتے ہیں.اور جہاں مفہوم کو صحیح طور پر ادا کرنے کا ذکر ہو وہاں رسول کریم کے الفاظ لائے جاتے ہیں.کیونکہ وہی پیغامبر عزت کا مستحق ہوتا ہے جو پیغام کو صحیح طور پر دوسرے تک پہنچا دیتا ہے.اگر آقا کچھ کہے اور نوکر جا کر کچھ کہہ دے.آقا تو یہ کہے کہ مَیں فلاں جگہ کل آئوں گا.اور وُہ جا کر یہ کہہ دے کہ وہ کہتے ہیں میں نہیں آئوں گا.تو وہ آقا کی نگا ہوںمیں ذلیل ہو جائے گا.عزت کے قابل وہی رسول
Page 349
ہوتا ہے جو پیغام کو صحیح طور پر پہنچانے والا ہو.دشمن کو الفاظ سے اتنی بحث نہیں ہوتی جتنی اس کے مطالب اور معانی سے بحث ہوتی ہے.اس لئے رسول کا کام ہوتا ہے کہ الفاظ کے صحیح معانی لوگوں کے سامنے بیان کر دے.اگر وہ بیان نہ کرے تو خطر ہ ہوتا ہے کہ لوگ دھوکا کھا جائیں.پس یہاں اصل سوال الفاظ کا نہیں بلکہ مفہوم کا سوال ہے کہ آیا وہ صحیح ہے یا نہیں.اس لئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ہمارا معزز رسول ہے.اگر اس میں یہ قابلیت نہ ہوتی کہ صحیح پیغام لوگوں تک پہنچاتا تو ہم اسے اتنی بڑی عزت کیوں دیتے.پس خالی الفاظِ قرآن نہیں.بلکہ الفاظ قرآن کی تشریح بھی اس میں شامل ہے.رسولٍ کریمٍ سے مراد جبریل نہیں بلکہ آنحضرت صلعم ہیں یہاں ایک ذوقی لطیفہ بھی ہے مفسرین نے رسول کریم سے جبریل مراد لیا ہے.(روح المعانی ،الکشافزیر آیت ھذا)مگر اللہ تعالیٰ نے اس کا ردّ ایک ایسے عجیب طریق سے کیا ہے کہ لطف آجاتا ہے.مسلمانوں میں عام طور پر رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کو رسول کریم ہی کہا جاتا ہے.اور جہاں بھی رسول کریم لکھا ہوا ہو ہر مسلمان کا ذہن فوراً اس طرف منتقل ہو جاتا ہے کہ اس سے رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم کے سوا اور کوئی مراد نہیں.پس مفسرین نے تو اس سے جبریل مراد لیا.مگر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں میں اس لفظ کا استعمال رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس قدر کثرت سے کر دیا.کہ اب رسول کریم کے الفاظ دیکھنے کے بعد کسی کا ذہن جبریل کی طرف منتقل ہی نہیں ہو سکتا.پھر یہ بات بھی ہے کہ جبریل کا کام تشریح کرنا نہیں بلکہ صاف الفاظ پہنچانا ہے اگر یہاں خالی الفاظ پہنچانے کا ذکر ہوتا تو امین کا لفظ رکھا جاتا کیونکہ الفاظ کو اُن کی اصل صورت میں لوگوں تک پہنچا دینا انسان کی امانت کو ظاہر کرتا ہے.لیکن یہاں کریم کا لفظ رکھا گیا.جو عزت پر دلالت کرتا ہے.اور پیغامبر کی عزت اسی وقت ظاہر ہو سکتی ہے جب وہ پیغام کی صحیح اور درست تشریح لوگوں تک پہنچا دے.فرماتا ہے اول تو تم دیکھو گے کہ یہ معزز اور برگزیدہ سمجھا جائے گا.بڑا عقلمند اور سمجھدار قرار پائے گا.پھر ذِیْ قُوَّۃٍ تم دیکھو گے کہ ایک دن یہ ذی قوۃ ہو جائے گا.آج یہ تمہیں کمزور نظر آتا ہے.اور تمہیں اس کی سچائی کا کوئی ثبوت نظر نہیں آتا.لیکن ہم تمہیں بتاتے ہیںایک دن یہ بڑا طاقتور ہو جائے گا.چنانچہ دیکھ لو یا تو یہ حالت تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوہلاک کرنے کے لئے آپ کے اردگردگھیرے ڈالے جاتے تھے اور یا صلح حدیبیہ کے معًا بعد آپ میں اتنی بڑی طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ آپ بڑے بڑے بادشاہوں کو اسلام کی دعوت دیتے اور انہیں تبلیغی خطوط بھجواتے ہیں.ان کے لئے یہ امر بالکل حیرت کا موجب تھا.کہ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے یہ کیا انقلاب واقعہ ہو گیا.کہ عرب کا وہ اُمّی انسان جسے بالکل حقیر سمجھا جاتا تھا اس قدر طاقت پکڑ گیا ہےکہ وہ ہمیں مخاطب کرتا اور اسلام
Page 350
میں داخل ہونے کی دعوت دیتا ہے آج کل اور زمانہ ہے.آج کل بادشاہوں کے پاس خط جائیں تو وہ اُن کو پڑھ کر اسی وقت پھینک دیں گے اور پروا بھی نہیں کریں گے.کہ کس نے کیا لکھا ہے.مگر اس وقت بڑے بڑے جابر بادشاہ تھے اور ان کو خط لکھنا کسی معمولی انسان کا کام نہیں ہو سکتا تھا.چنانچہ کسریٰ نے جب یہ خط پڑھا تو وہ آگ بگولہ ہو گیا.اسے اپنی ہتک محسوس ہوئی.اور اس نے نہایت غصہ کا اظہار کیا(تاریخ طبری زیر عنوان ذکر خروج رسل رسول اللہ الی الملوک).آج کل قیاس بھی نہیں کیا جا سکتا کہ اس زمانہ میں بادشاہوں کو خط لکھنا کتنا مشکل کام تھا.کیونکہ اب زمانہ اور ہے آج جو شخص چاہے بادشاہوں کو خط لکھ سکتا ہے.بلکہ جنگ سے پہلے اگر کوئی ہٹلر،میسولینی یا روزویلٹ کو خط لکھنا چاہتا تو آسانی سے لکھ سکتا تھا.مگر وہ زمانہ ایسانہیں تھا اس زمانہ میں بادشاہوں کو کسی معمولی آدمی کا خط لکھنا اپنی موت کو خود بلانے کے مترادف تھا.اصل بات یہ ہے کہ حقیقت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بہت دفعہ دھوکا لگ جاتا ہے.مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی اسی بات پر بہت فخر کیا کرتے تھے کہ میں وائسرائے کو خط لکھتا ہوں تو وُہ میرے خط کا جو اب دے دیتا ہے.حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ اس میں کون سی بڑی بات ہے.اُسے تو اگر ایک چوڑھا بھی خط لکھے تو وہ جواب دےدےگا ڈئیر سَرDEAR SIR! مخصوص الفاظ ہیں جو ہر خط پر لکھے جاتے ہیں.پڑھنے والا سمجھتا ہے کہ میری بڑی عزت ہو گئی حالانکہ یہ عام الفاظ ہوتے ہیں مگر مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی اس دھوکہ میں رہے کہ وائسرائے مجھے خط لکھتے ہیں تو مہربانِ من کہہ کر مخاطب کرتے ہیں.حالانکہ ان کے ہاں اس کے سوا اور کوئی لفظ ہی نہیں.وُہ ایک چوڑھے کو بھی خط لکھیں گے تو اوپر یہی الفاظ لکھیں گے.ڈپٹی کمشنر کو لکھیں گے تو اُسے بھی یہی لکھیں گے تو بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن سے لوگ دھوکا کھا جاتے ہیں.اسی رنگ کی ایک اور مثال مجھے یاد آگئی.مَیں نے ایک دفعہ ایک احمدی کو دیکھا کہ وہ دُوسرے سے بحث کر رہا تھا.کہ کیا تم نے مجھے کبھی جھوٹ بولتے دیکھا.اور اس کے متعلق وُہ فَقَدْ لَبِثْتُ فِیْکُمْ عُمُرًا مِّنْ قَبْلِہٖ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ (یونس:۱۷ )کو بار بار پیش کرتا کہ مَیں تم میں اتنا عرصہ رہا ہوں.کیا تم نے مجھے جھوٹ یا فریب سے کام لیتے دیکھا.حالانکہ یہ استدلال اس کے لئے ہوتا ہے جو قوم کے سامنے آچکا ہوتا ہے.نہ کہ جو شخص اٹھے اس سے اپنی صداقت کا استدلال کرناشروع کر دے.جوشخص قوم کی نظروں کے سامنے آ جائے.اس کے لئے بے شک یہ دلیل ہے لیکن دوسرے کے لئے نہیں.آنحضرت صلعم کے ذِیْ قُوَّةٍ اور ذِی الْعَرْش مکین ہونے کا ایک نظارہ اسی طرح کسی بڑے آدمی کو چٹھی بھیج دینے کی اہمیت موجودہ زمانے میں نہیں رہی اور یہی وجہ ہے کہ بعض مسلمان جب ان باتوں کو
Page 351
پڑھتے ہیں تو حیران ہوتے ہیں کہ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو چٹھیاں بھجوا دیں تھیں.تو اس میں کون سی عجیب بات ہو گئی.وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اُس زمانہ میں بادشاہوں کو چٹھی لکھنا بڑی خطرناک بات ہوا کرتی تھی اور بادشاہ بعض دفعہ ناراض ہو کر چٹھی بھجوانے والے کو مروا دیا کرتے تھے.لیکن آج کل کا زمانہ اور ہے.اب اگر روزانہ بھی چٹھیاں لکھی جائیں تو کوئی اہم بات نہیں سمجھی جا سکتی.پھر اس بات پر بھی غور کرنا چاہیے کہ رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم کے خطوط جب مختلف بادشاہوں کو پہنچے تھے تو انہوں نے ان خطوط کا لکھنا ایک معمولی بات سمجھی تھی.یا اس کا ان کے قلوب پر خاص اثر ہوا تھا تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ جب رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم کا خط قیصر کو پہنچا تو اس نے ابو سفیان کو بلایا.اور اس سے کئی باتیں دریافت کیں.جب سب باتیں دریافت کر چکا تو ابو سفیان کی زبان سے بے اختیار یہ الفاظ نکلے کہ لَقَدْ اَمِرَ اَمْرُ ابْنِ اَبِیْ کَبْشَةَ اِنَّہُ یَخَافُہُ مَلِکُ بَنِی الْاَصْفَرِ (بخاری کتاب بدء الوحی باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ )کہ اس شخص کا معاملہ تو بہت بڑھ گیا ہے کہ رومیوں کا بادشاہ بھی اس سے خوف کھاتا ہے اسی طرح قیصر کو جبکہ وہ شام پر اپنی فوجیں لے کر آیا ہوا تھا.یہ لکھنا کہ اگر تو ایمان نہیں لائے گاتو اِنَّ عَلَیْکَ اِثْمُ الْاَرِیْسِیِّیْنَ (بخاری کتاب بدء الوحی باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ ) یعنی تیرے ماتحت جس قدر لوگ ہیں ان سب کا گناہ تیرے سر پر ہو گا بتا رہا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا خط یہ جانتے ہوئے لکھا تھا کہ ممکن ہے وہ فوج لے کر ہم پر چڑھائی کر دے.اور ممکن ہے وہ مجھے مارنے کا فیصلہ کر ے.مگر آپ نے اس بات کی کوئی پروا نہ کی.اور بڑے بڑے بادشاہوں کو کھلے طور پر سنا دیا کہ اگر تم ایمان لائو گے تو اس میں تمہارا فائدہ ہے اور اگر انکار کرو گے تو خدا تعالیٰ کے حضور ایک مجرم کی حیثیت میں کھڑے ہو گے.تو فرماتا ہے آج محمد رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کوحقارت کی نظر سے دیکھتے ہو.لیکن عنقریب تم دیکھو گے کہ وُہ ذِیْ قُوَّۃٍ ہو جائے گا بڑے بڑے بادشاہ اس کے خوف سے کانپیں گے اور غیر معمولی عظمت اسے حاصل ہو جائے گی.ذِیْ قُوَّةٍ کہہ کر عِنْدَ ذِی الْعَرْشِ مَکِیْنٍکہنے کی وجہ عِنْدَ ذِی الْعَرْشِ مَکِیْنٍ پھر ذِیْ قُوَّۃٍ ہونے کے بعد تم اس میں ایک زائد بات بھی دیکھو گے.ذِیْ قُوَّۃٍ ہونے والے عام طور پر دین اور مذہب کو نظر انداز کر دیتے ہیں.اور وُہ طاقتور ہو کر ضعیفوں کے حقوق غصب کر لیتے ہیں مگر فرمایا یہ ایسا نہیں ہو گا.دراصل مکہ والوں کے دلوں میں بھی وہی شبہ تھا.جو یورپ والوں کو پیدا ہوا کہ محمد رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم بڑائی حاصل کرنے یا بادشاہت اور حکومت اپنے قبضہ میں لینے کے لئے سب کچھ کر رہے ہیں.اسی لئے انہوں نے ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام بھجوایا تھا کہ اگرآپ دولت چاہتے ہیں تو ہم اتنی دولت آپ کے
Page 352
لئے جمع کر دیتے ہیں کہ عرب میںاور کسی کے پاس اتنی دولت نہ ہو گی.اور اگر آپ حکومت چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنا بادشاہ ماننے کے لئے تیار ہیں.مگر ہمارے بُتوںکو بُرا بھلا نہ کہا جائے(السیرة النبویة لابن ہشام زیر عنوان قول عتبة بن ربیعة فی امررسول اللہ ).تو مکّہ والے سمجھتے تھے کہ یہ سب پیشگوئیاں اس لئے کی جاتی ہیں کہ حکومت حاصل کرنے کی خواہش دل میں پائی جاتی ہے.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم یہ خیال کرتے ہو کہ اس نے اپنے ذی قوۃ ہونے کے متعلق اس لئے خبریں دینی شروع کر دی ہیں کہ یہ بادشاہ بننا چاہتا ہے یہ تو ٹھیک ہے کہ یہ بادشاہ ہو گا مگر اپنی خواہش اور مرضی کے مطابق نہیں ہو گا بلکہ جب یہ بادشاہ ہو گا تو تم دیکھو گے کہ یہ تقویٰ میں پہلے سے بھی بڑھ جائے گا.اور جو شخص بادشاہت کے بعد نیکی اور تقویٰ میں پہلے سے بھی بڑھ جائے اس کے متعلق یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وُہ حکومت کی ذاتی طور پر خواہش رکھتا تھا.بلکہ اس کے متعلق یہی سمجھا جائے گا کہ خدا نے خود اس مقام پر اسے کھڑا کیا ہے.فرماتا ہے ہم بھی جب محمد رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کو بادشاہت دیںگے تو وہ غریب پرور ہو گا.منکسر المزاج ہو گا.وہ خدمت خلق کرنے والا ہو گا.وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ادا کرنے والا ہو گا.گویا بادشاہت اس کی نماز کو بڑھا دے گی.اس کے روزہ کو ترقی دے گی.اس کے صدقہ اور اس کے حج اور اس کی دوسری نیکیوں میں اضافہ کر دے گی.پس ذِیْ قُوَّۃٍ کے ساتھ عِنْدَ ذِی الْعَرْشِ رکھ کر دونوں کا جوڑ بتا دیا.لیکن ذِیْ قُوَّۃٍ میں ایک خوبی تھی اور ایک نقص تھا.خوبی تو یہ تھی کہ جو شخص ذی قوۃ ہو وہ دوسروں پر غالب آجاتا ہے اور نقص یہ ہوتا ہے کہ طاقت حاصل کرنے کے بعد انسان دوسروں کے حقوق کو دلیری سے دبا لیتا ہے.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم ہمارے رسول میں یہ بات نہیں دیکھو گے.اس کی ذی قوّۃ والی حالت اسے مغرور نہیں کرے گی.بلکہ وہ اسے عِنْدَ ذِی الْعَرْشِ مَکِیْنٍ بنا دے گی.اس کی بادشاہت اسے نیکیوں میں اَور بڑھا کر اسے خدا تعالیٰ کا اور بھی مقرب بنا دے گی.اس کا تقویٰ میں بڑھنا اس کا دین میںترقی کرنا اس کا لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کا خیال رکھنا سب باتیں اس کا ثبوت ہوں گی کہ اس کی بادشاہت دنیوی بادشاہت نہیں.اور اسکی بادشاہت اسے دین سے بے بہرہ کرنے کا موجب نہیں بلکہ اسے تقویٰ اور طہارت اور عرفان میں ترقی دینے کا موجب ہے.مطاع کے ساتھ امین کا لفظ لانے میں حکمت پھر فرماتا ہے مَطَاعٍ ثَمَّ اَمِيْنٍ.یہاں بھی اللہ تعالیٰ دو متضاد باتیں لے آیا ہے.اول مُطَاع اور پھر ساتھ ہی اَمِیْن.مُطَاع کا لفظ بتا رہا ہے کہ یہ سب لوگ اس کی باتیں ماننے پر مجبور ہوں گے.مگر فرمایا گو یہ لوگوں کا مطاع ہو گا لیکن ساتھ ہی اَمِیْن بھی ہو گا.جو شخص مطاع ہو جاتا ہے اس کے اندر بعض دفعہ غرور اور کبر پیدا ہو جاتا ہے.کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ میں جو چاہوں کر سکتا ہوں.کوئی شخص میرے
Page 353
فیصلے کے خلاف اپنی زبان نہیں کھول سکتا.مگر فرماتا ہے جب خدا اس کے ہاتھ میں لوگوں کی گردنیں دے گا.ان کی عزتیں دے گا.ان کے مال دے گا.تو تم دیکھو گے یہ ہر شخص کا حق پُوری دیانتداری کےساتھ ادا کر ے گا.گویا جہاں خدا کا حق پوری طرح ادا کرنے کے لحاظ سے یہ عِنْدَ ذِی الْعَرْشِ مَکِیْنٍ ہو گا.وہاں بندوں کے حقوق ادا کرنے کے لحاظ سے یہ امین بھی ہو گا.ان چار الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے حکومتی اخلاق کا ایسا زبردست نقشہ کھینچا ہے کہ جس کی مثال دنیا کے پردہ پر نہیں مل سکتی.فرماتا ہے یہ بادشاہ ہو جائے گا.مگر خدائی بادشاہت کا جوا اپنی گردن پر رکھے گا.یہ حاکم ہو جائے گا مگر سب لوگوں کے حقوق پورے انـصاف کے ساتھ ادا کرے گا.گویا اطاعت اللہ اس میں اس وقت پائی جائے گی جب اس کے پاس طاقت ہو گی.اور شفقت علیٰ خلق اللہ اس میں اس وقت پائی جائے گی.جب بندے اس کے رحم پر ہوں گے.غرض کَرِیْم.ذِیْ قُوَّۃِ.عِنْدَ ذِی الْعَرْشِ مَکِینٍ.مُطَاع.اَمِین رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم کی صفات ہیں جو ان آیات میںبیان کی گئی ہیں.ان آیات کے ایک اور معنے بھی ہیں.اور وہ یہ کہ آپ نے وہ عزت پائی کہ کسی نے کیا پانی ہے.دنیا کے بادشاہوںکو بھی وہ نصیب نہیں ہے.ذِیْ قُوَّۃٍ ایسے ہوئے کہ قیصرو کسریٰ کی بادشاہتوں کو الٹ دیا.مگر ساتھ ہی مَکِیْنٍ عِنْدَ ذِی الْعَرْشِ بھی ہیں کہ آج تک آپ کی ہتک کرنے والے ذلیل کئے جاتے ہیں.مُطَاع ہیں کہ جب سب بادشاہوں کے تخت الٹے جا رہے ہیں.آپ کے تخت کو دوبارہ ایک مامور کے ذریعہ سے قائم کیا جا رہا ہے.اٰمِیْن ہیں کہ جس کلام کو پہنچانا آپ کے ذمہ لگایا گیا تھا آج تک محفوظ ہے.اور روحانی طور پر اس کی حفاظت کا سامان کیا جا رہا ہے.اس میںاگرآپ کی قوتِ قدسیہ کا دخل نہیں تو اور کیاہے.وَ مَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُوْنٍۚ۰۰۲۳ اور تمہارا ساتھی ہر گز مجنون نہیں.تفسیر.چونکہ ایسی پیشگوئیوں کو سن کر بعض لوگ کہہ دیا کرتے ہیں.کہ یہ شخص جو ایسی باتیں کرتا ہے پاگل ہے.اِس لئے رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم کے مذکورہ بالا اخلاق کو بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ وَ مَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُوْنٍ تم اس شبہ میں مبتلا نہ ہونا کہ یہ پاگل ہے.کیونکہ وہ صَاحِبُکُمْ ہے.تمہارے ساتھ رہا ہے.کہیں باہر سے
Page 354
نہیں آیا.اور تم خود اس کی نیکی اور تقویٰ اور عقل اورا صابت رائے کے گواہ رہے ہو.پھر اب کس وجہ سے اسے پاگل قرار دیتے ہو.آخر عقل سے جنون کی طرف رجوع یا کسی صدمہ سے ہوتا ہے یا بیماری سے یا تدریجی طور پر ہوتا ہے.رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم تمہارے ساتھ رہے ہیں اور ان میں سے کوئی بات بھی آ پ میں نہیں پائی جاتی.پھر ان کو پاگل تم کس طرح کہتے ہو.یہ قرآن کریم کا معجزانہ کمال ہے کہ ایک لفظ میں دلیل بیان کر دیتا ہے.اس جگہ صرف صَاحِبُکُمْ کے مختصرسے لفظ سے مجنون ہونے کے الزام کی نفی کر دی.یعنی اس طرف توجہ دلا کر کہ یہ تو تمہارا صاحب یعنی دوست اور مشیر کار اور امانتدار کہلاتا تھایکد م اسے جنون آخر کہاں سے آیا.اور اس دعویٰ کے بعد اس کے مجنون ہونے کا فتویٰ کیوں لگانے لگ گئے.اس سے پہلے تواسے اپنا آقا اور سردار کہا کرتے تھے.اور اپنا لیڈر تسلیم کرتے تھے.اور بڑا عقلمند اورسمجھدار قرار دیتے تھے.وَ لَقَدْ رَاٰهُ بِالْاُفُقِ الْمُبِيْنِۚ۰۰۲۴ اور اس نے اس (غیب ) کو یقیناً کھلے اُفق میں دیکھا ہے.وَ مَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِيْنٍۚ۰۰۲۵ اور وہ غیب (کی خبریں بتانے) میں ہر گز بخیل نہیں.حَلّ لُغَات.اَلْاُفُقُّ اَلْاُفُقُّ وَالْاُفْقُ اَلْاٰفَاقُ کا مفرد ہے.اور اَلْاَفَاقُ کے معنے ہیں اَلنَّوَاحِیْ اطراف (اقرب) اور اُفُقُ الْمُبِیْنِ.نَاحِیَۃُ الْمَشْرِقِ کو کہتے ہیں.کیونکہ سورج مشرق سے ہی ظاہر ہوتا ہے.ضَنِیْنٍ مَا ھُوَ عَلَی الْغَیْبِ بِضَنِیْنٍ اَیْ مَا ھُوَ بِبَخِیْلٍ یعنی ضَنِیْنٍ کے معنی ہیں بخیل اور مَا ھُوَ عَلَی الْغَیْبِ بِضَنِیْنٍکے معنے ہیں کہ وہ غیب بیان کرنے پر بخیل نہیں.(مفردات) تفسیر.مجنون کے الزام کو ردّ کر کے اب بتاتا ہے کہ جب محمد رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کا دَورِ نبوت ایک لمبے عرصہ تک کے لئے ہے تو وہ اس لمبے عرصہ کے متعلق پیشگوئیاں کیوں نہ کرے.وہ اپنے دعویٰ کی وجہ سے مجبور ہے کہ جو باتیں تم کودُور اور خلاف عقل نظر آتی ہیں اُن پر روشنی ڈالے کیونکہ وُہ باتیں اس کے زمانۂ بعثت کے اندر شامل ہیں تمہارے لئے وہ زمانۂ غیب ہے لیکن اس کے جہان پر وہ ظاہر ہے اور اس کی دنیا کے لئے بطور افقِ مبین کے ہے جسے وہ دیکھ رہا ہے اور جن خبروں کو وہ بتا رہا ہے وہ مشرق سے تعلق رکھتی ہیں.
Page 355
افق مبین سے مراد مشرق مشرق کا استدلال اس سے ہوتا ہے کہ گو افق تو ہرجہت بعیدہ کو کہتے ہیں لیکن حدنظر جہاں آسمان اور زمین کو ملتے ہوئے دیکھتی ہے وہ ہر سمت افق تو ہوتی ہے مگر افق مبین نہیں ہوتی یعنی کھولنے اور ظاہر کرنے والی افق.کھولنے اور ظاہر کرنے والی افق مشرق ہی کی ہوتی ہے جدھر سے سورج نکلتا ہے اور اندھیروں کو پھاڑ دیتا ہے پس افق مبین کے الفاظ اداکر کے نہ صرف زمانہ بعیدہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے بلکہ مشرق کی طرف کے ظہور کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے.پھر فرماتا ہے کہ اس کی بتائی ہوئی خبریں گو تم کو عجیب معلوم ہوتی ہیں مگر تمہیں اِسے مجنون کہنے کا حق نہیں ہے کیونکہوَ مَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِيْنٍ اس نے غیب کی ایک ہی خبر نہیں دی کہ تم کہہ دو یہ تو پاگل ہے بلکہ یہ غیب پر بخیل نہیں ہے یعنی اس نے آئندہ حالات سے تعلق رکھنے والی بہت سی اہم خبریں دی ہیں جن میں سے کئی پوری بھی ہو چکی ہیں.اگر ایک ہی خبر ہوتی جو اس نے دی ہوتی اور اگر محمد رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ کہا ہوتا کہ چونکہ تیرہ سو سال کے بعد ایسا ہو جائے گا اس لئے تم مجھے مان لو تو تم کہہ سکتے تھے کہ یہ پاگل ہے مگر اب تم یہ بات نہیں کہہ سکتے کیونکہ وَ مَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِيْنٍ.یہ پہلی خبر نہیں ہے جو اس نے دی ہو بلکہ اور بھی یہ بہت سی خبریں دے چکا ہے اور وہ خبریں پوری بھی ہو چکی ہیں پس تم ان خبروں پر قیاس کر کے کہہ سکتے ہو کہ یہ بات بھی ایک دن پوری ہو جائے گی.تمہارا یہ حق نہیں ہے کہ تم اسے پاگل کہو.آج کل جو جھوٹے مدعی کھڑے ہو گئے ہیں اُن سے جب ہماری بحث ہوتی ہے کہ بتائو تمہاری کون کون سی پیشگوئی پوری ہوئی تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ تم مرزا صاحب کی فلاں بات مانتے ہو یا نہیں جس نے ابھی تین سو سال کے بعد پورا ہونا ہے جب تم اس بات کو مانتے ہوتو ہماری بات کیوں نہیں مان لیتے.ہم اُنہیں یہی کہا کرتے ہیں کہ اگر مرزا صاحب کی صرف یہی ایک پیشگوئی ہوتی کہ تین سو سال کے بعد ایسا ہو جائے گا تو یقیناً یہ آپ کی صداقت کا کوئی قطعی ثبوت نہ تھا.آپ کی صداقت کا ثبوت تو یہ ہے کہ آپ نے اس کے علاوہ اور بھی کئی پیشگوئیاں کیں جو پوری ہو گئیں اُن پر قیاس کر کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پیشگوئی بھی ایک دن پوری ہو جائے گی مگر تمہاری حالت تو یہ ہے کہ تمہاری اب تک کوئی پیشگوئی پوری نہیں ہوئی.جتنی پیشگوئیاں ہیں سب آئندہ زمانوں سے تعلق رکھتی ہیںچنانچہ جس قدر مدعی ہیں اُن کا سارا زور اسی پر ہوتا ہے کہ اگر مَیں اُن کو مان لوں تو اسلام کو ترقی حاصل ہو جائے گی مگر وہ یہ نہیں سوچتے کہ میں ان کو کس طرح مان لوں جب کہ اُن کی صداقت کا کوئی ثبوت ہی نہیں.تو فرماتا ہے وَ مَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِيْنٍ.سچے مدعی کو پہچاننے کا ایک اصول سچے مدعی کو پہچاننے کا یہ ایک زبردست اصول ہے کہ اس کی بعض پیشگوئیاں قریب زمانہ سے تعلق رکھتی ہیں اور بعض بعید زمانہ سے تعلق رکھتی ہیں مثلاً حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پیشگوئی
Page 356
فرمائی ہے کہ روس کا عصا مجھے دیا جائے گا یا تین سو سال میں جماعت احمدیت کا ساری دنیا پر غلبہ ہو جائے گا (تذکرۃ الشہادتین روحانی خزائن جلد ۲۰ صفحہ ۶۷).اِ ن پیشگوئیوں کو دشمن دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ محض ڈھکونسلے ہیں کون ان باتوں کو مان سکتا ہے.ایسے لوگوں کا جواب اللہ تعالیٰ نے اس آیت میںدیا ہے کہ یہ غیب پر بخیل نہیں ہے اس نے صرف ایک یا دو خبریں نہیں دیں جو ابھی صدیوں بعد پوری ہونے والی ہیں بلکہ یہ اور بھی کئی قسم کی خبریں دے چکا ہے جو پوری ہو چکی ہیں اُن کو دیکھتے ہوئے تم کیوں یہ تسلیم نہیں کرتے کہ جب وہ باتیں پوری ہو گئی ہیں تو یہ باتیں بھی پوری ہو جائیںگی مجھے اچھی طرح یاد ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پاس آ کر جب کوئی شخص کہتا کہ مجھے کوئی نشان دکھایا جائے تو آ پ فرماتے پہلے نشانات سے تم نے کیا فائدہ اٹھایا ہے کہ تمہیں اور نشان دکھایا جائے(ملفوظات جلد ۵ صفحہ ۶۴۳.۶۴۴).یہی بات اللہ تعالیٰ نے اس جگہ بیان فرمائی ہے کہ وَ مَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِيْنٍ.بظاہر تم اسے ایک پاگل کی بڑ قرار دیتے ہو کہ دُور مشرق میں ایک مامور آئے گا جس کے ساتھ اسلام کی ترقی وابستہ ہو گی لیکن اگر یہ پاگلوں والی بات ہوتی تو اس کی صداقت کا کوئی اور ثبوت نہ ہوتا.لیکن جب ا س کی پیشگوئیاں بکثرت ایسی موجود ہیں جو پوری ہو چکی ہیں تو تمہیں ماننا پڑے گاکہ یہ پاگل نہیں ہے اور پھر جیسا کہ پہلے بتایا گیا ہے اس کے اخلاق اور اس کی پہلی زندگی کے حالات مزید ثبوت ہیں اس بات کا کہ یہ مجنون نہیں ہے.وَ مَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطٰنٍ رَّجِيْمٍۙ۰۰۲۶ اور نہ وہ (یعنی اس پر نازل ہونے والا کلام ) دھتکارتے ہوئے شیطان کی (کہی ہوئی) بات ہے.حَلّ لُغَات.رَجِیْمٌ رَجِیْمٌ رَجَمَ میں سے ہے اور رَجَمَہٗ کے معنے ہوتے ہیں رَمَاہُ بِالْحِجَارَۃِ.اُسے پتھر سے مارا (۲)قَتَلَہٗ.اس کو قتل کر دیا (۳)قَذَفَہٗ.اس پر تہمت لگائی (۴)لَعَنَہٗ.اس پر لعنت کی (۵)شَتَمَہٗ.اس کو گالی دی (۶)ھَجَرَہٗ.اس کو چھوڑ دیا (۷)طَرَدَہٗ.اس کو دھتکار دیا(اقرب) پس رَجِیْم کے معنے ہوں گے دھتکارا ہوا (۲)چھوڑا ہوا (۳)ملعون (۴)تہمت لگایا ہوا (۵)گالی دیا ہوا (۶)پتھرائو کیا ہوا.تفسیر.یہاں ایک نہایت لطیف اور زبردست ثبوت پیش کیا گیا ہے جو صادق اور کاذب مدعی میں مابہ الامتیاز کا کام دیتا ہے مگر چونکہ یہ ثبوت باریک ہوتا ہے اس لئے جب تک ایک ماہر فن اس دلیل کو صحیح طور پر پیش نہ کرے دوسرا شخص سمجھ نہیں سکتا.رَجِیْم کے معنے ہوتے ہیںدھتکارا ہوا پس وَ مَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطٰنٍ رَّجِيْمٍکے یہ
Page 357
معنے ہوئے کہ یہ دھتکارے ہوئے شیطان کا قول نہیں ہے.یعنی دو ہی الزام کفا ر لگا سکتے ہیں ایک یہ کہ نعوذ باللہ آپ پاگل ہیںاس کا جواب اوپر گزر چکا ہے دوسرے یہ کہ نعوذ باللہ آپ بد اور شیطان سے تعلق رکھتے ہیں اس کا بھی وَ مَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِيْنٍ سے رد ہو گیا کیونکہ جس کی کئی پیشگوئیاں پوری ہو چکی ہوں وہ شیطان سے تعلق رکھنے والا کس طرح کہلا سکتا ہے شیطان کو علم غیب کہاں سے آیا وہ تو دھتکاراہوا ہے چنانچہ قرآن کریم نے دوسری جگہ اس مضمون کو یوں بیان فرمایا ہے اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِزِيْنَةِ ا۟لْكَوَاكِبِ.وَ حِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ مَّارِدٍ.لَا يَسَّمَّعُوْنَ اِلَى الْمَلَاِ الْاَعْلٰى وَ يُقْذَفُوْنَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ.دُحُوْرًا وَّ لَهُمْ عَذَابٌ وَّاصِبٌ.اِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَاَتْبَعَهٗ شِهَابٌ ثَاقِبٌ (الصّٰفّت:۷ تا ۱۱) یعنی ہم نے ورلے آسمان کو ستاروں کے ساتھ مزین کیا ہے اور ہم نے اسے ہر سرکش شیطان سے محفوظ کیا ہے وہ خُدا کے مقربوں کی بات نہیں سُن سکتے (کجا یہ کہ خدا تعالیٰ کی بات سُنیں) اور ہر طرف سے اُن پر پتھرائو ہوتا ہے تاکہ انہیں دُور کر دیا جائے اور انہیں مستقل عذاب ملتا ہے.ہاں اگر کوئی بات (مقربین سے) اُچک لے تو اللہ تعالیٰ اُس پر ایک چھید دینے والا ستارہ پھینکتا ہے جو اُسے تباہ کر دیتا ہے پس اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ علمِ غیب شیطانوں کو نہیں ہوتا.اگر جھوٹے ملہمین کسی کی بات کو اپنی طرف منسوب کر کے وہ غیب دان بننا بھی چاہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو سز ا دے کر تباہ کر دیتا ہے.پس جبکہ محمد رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم غیب کے بیان کرنے میں بخیل نہیں یعنی کثرت سے غیب بیان کرتے ہیں تو ان کا تعلق شیطان سے کس طرح ہو سکتا ہے وہ تو لازمًا خدا تعالیٰ کے مامور ہی سمجھے جا سکتے ہیں.ایک دلیل اور بھی اس جگہ دی گئی ہے اور وہ یہ کہ رَجِیْم دھتکارے ہوئے کو کہتے ہیں.پس اس جگہ کفار کو اس طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے کہ یہ مدعی تو روز بروز ترقی کر رہا ہے جو شخص شیطان سے تعلق رکھتا ہے وہ تو ذلیل ہوا کرتا ہے نہ کہ ترقی کرتا جاتا ہے.ضمنی طور پر اس جگہ یہ ذکر کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ بعض لوگ اس دلیل کو صحیح طور پر نہ سمجھنے کی وجہ سے دھوکا کھا جاتے ہیں اور اُن کے لئے سچے اور جھوٹے مدعی میں امتیاز کرنا مشکل ہو جاتا ہے.کیونکہ جو مدعی بھی کھڑا ہو گا خواہ وہ جھوٹا ہی ہو کچھ نہ کچھ لوگ اس کے ساتھ ضرور مل جاتے ہیں اور پھر عام طور پر وہ اس بات کو اپنی صداقت کے ثبوت کے طور پر پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھو ہم اکیلے تھے اب ہمارے ساتھ اس قدر آدمی شامل ہیں.میں نے دیکھا ہے عام طور پر ہماری جماعت کے آدمی بھی بعض دفعہ ایسے موقع پر گھبرا جاتے ہیں مثلاً میاں عبداللہ تیما پوری کہہ دیتے ہیں کہ میں پہلےاکیلا تھا مگر اب مجھے ماننے والے اتنے ہو گئے ہیں یا میاں غلام محمد کہہ دیتے ہیں میرے ساتھ اتنے لوگ ہیں اوریہ میر ی سچائی کا ثبوت ہے اگر میں جھوٹا ہوتا تو اللہ تعالیٰ مجھے یہ کامیابی کیوں عطا کرتا.درحقیقت یہ
Page 358
دلیل بہت نازک ہے اور جس طرح چٹانوں میں سے جہاز کو حفاظت سے گزارنا پڑتا ہے اسی طرح اس دلیل کے متعلق یہ خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں کوئی شخص دھوکا نہ کھا جائے اور وہ اپنے ایمان کو برباد نہ کر لے.انبیاء کی جماعتوں کی تین صفات درحقیقت اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ یہ دلیل اس وقت مکمل ہوتی ہے جب تین باتیں اس میں پائی جائیں.بغیر ان تین پہلوئوں کے یہ دلیل کسی مدعی کی طرف سے اپنی صداقت کے ثبوت میں پیش نہیں کی جا سکتی.اوّلؔ اُس کی جماعت میں تقویٰ و طہارت اور نیکی کا ایک معیار ہونا چاہیے.خالی چند آدمیوں کا ساتھ مل جانا یا دعویٰ پر ایمان لے آنا کسی مدعی کی صداقت کا ثبوت نہیں ہو سکتا.صداقت کے ثبوت کے لئے ضروری ہے کی تقویٰ و طہارت اور نیکی کا معیار پیش کیا جائے جس سے پتہ لگے کہ اس مدعی پر ایمان لانے والوں کا خدا سے تعلق ہو گیا ہے.یہ تو لوگ مان سکتے ہیں کہ ایک شخص کو نیکی کا خیال تھا اور اس کے دل میں یہ احساس تھا کہ میں ترقی کروں مگر ایک دن اس کا دماغ خراب ہو گیا لیکن یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اُس سے جو شخص بھی جُڑتا جائے اُس کی زندگی میں ایک تغیر پیدا ہوتا چلا جائے اور نیکی اور تقویٰ اس کے قلب میں سرائت کر جائے.پس کسی مدعی کو ماننے والوں کی نیکی اور تقویٰ کا معیار ایسا بلند ہو نا چاہیے اور اُن کے اندر اللہ تعالیٰ کی خشیت اور بنی نوع انسان کے لئے قربانی اور ایثار کا اس قدرمادہ ہونا چاہیے کہ اسے دیکھ کر انسان خود بخود کہہ اُٹھے کہ جو لوگ خودایسے ایسے ہیں ان کا مطاع تو بہرحال خدا کا راستباز انسان ہو گا.جب تک یہ علامت کسی جماعت کے اندر نہ ہو اس وقت تک اس کے شیطانِ رجیم سے الگ ہونے کا کوئی یقینی ثبوت نہیں ہو سکتا.دوسرےؔ شیطان رجیم کے معنے ہیں ایسا شیطان جو ذلیل ہو کیونکہ جس کو رجم ہوتا ہے وہ لوگوں کی نگاہ میں ذلیل ہو جاتا ہے مگر سچے نبی کی یہ علامت ہوتی ہے کہ اس کی جماعت بالقوہ اعزاز اپنے اندر رکھتی ہے اور اس کے افراد کے اندر ترقی کی ایسی قابلیتیں پائی جاتی ہیں کہ ہر دیکھنے والااس یقین سے پُر ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ ایک دن دنیا پر غالب آجائیں گے.جیسے حضرت صالح علیہ السلام کے متعلق قرآن کریم میں ذکرآتا ہے کہ انہیں کفار نے یہ کہا کہ یَاصَالِحُ قَدْ کُنْتَ فِیْنَا مَرْجُوًّا قَبْلَ ھٰذَا (ہود:۶۳) اے صالح تجھ پر تو ہماری بڑی امیدیں تھیں اور ہم سمجھتے تھے کہ تُو قوم کو ترقی کی طرف لے جائے گا.یہ امید تو لوگ رکھتے ہی ہیں دعویٰ کے بعد جب ایک جماعت اس کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے اُس وقت اُن کے دماغوں میں ایسی تازگی اور ان کے دلوں میں ایسی ہمت بلند پیداہو جاتی ہے کہ وہ کسی روک کی پروا نہیں کرتے.مگر اس ہمت بلند سے مراد خیالی پلائو پکانا نہیں.جیسا کہ بعض مدعیوں نے کہہ دیا کہ دنیا کی
Page 359
حکومت ہمیں ملے گی اور جب اُن کے ایک مرید نے کہا کہ مجھے کیا ملے گا تو اُسے کہا گیا کہ پنجاب کی بادشاہت.بلکہ ہمت بلند سے مراد یہ ہے کہ وہ ایسے طریق اختیار کرتے ہیں جن سے دنیا یہ سمجھنے پر مجبور ہوتی ہے کہ اُن کی طرف سے دنیا کو فتح کرنے کے ذرائع عمل میں لائے جا رہے ہیں اور وہ اس غلبہ کے لئے معقول جدو جہد کر رہے ہیں.پس سچے مدعی کی دوسری علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کی جماعت میں رجم نہیں پایا جاتا بلکہ اقدام پایا جاتا ہے.رجم کے معنے ہیں بھاگنا.جس پر پتھرائو ہوتا ہے وہ اس سے بچنے کے لئے بھاگتا ہے.مگر صادق مدعی کی جماعت دشمنوں سے بھاگا نہیں کرتی بلکہ یوں معلوم ہوتا ہے وہ حملہ کر کے اُن کو کھا جانے کی کوشش کر رہی ہے.تیسریؔ بات اس کے اندر یہ بتائی گئی ہے کہ جس پر پتھرائو ہووہ سامنے نہیں آتا بلکہ اِدھر اُدھر چُھپتا پھرتا ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں مومنوں سے فرماتا ہے کہ وہ خَنَّاس کے وسوسوں سے بچنے کے لئے ہمیشہ دعا کرتے رہا کریں اور خنّاس وہی ہوتا ہے اَلَّذِيْ يُوَسْوِسُ فِيْ صُدُوْرِ النَّاسِ.مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ جو لوگوں کے سینوںمیں وسوسے پیدا کرتا اور خود چھپ جاتا ہے اِسی مناسبت سے ان آیات میں خُنَّس کا ذکر کیا گیا ہے.مگر انبیاء کی جماعتوں میں کوئی اخفا نہیں ہوتا وہ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی تعلیم کو لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نے اس تعلیم پر جو جواعتراض کرنا ہے وہ بے شک کر لو مگر دوسروں میں یہ ہمت نہیں ہوتی.وہ ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ اُن کی تعلیم کا لوگوں کو علم نہ ہو.جیسے بہائی ہیں کہ وہ ہمیشہ اپنے مذہب کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ کبھی سپاہی بھی لوگوں سے چھپتا ہے.سپاہی تو وردی پہن کر لوگوں کے سامنے پھرتا ہے مگرچور اِدھر اُدھر چھپتا پھرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ کوئی اُسے دیکھ نہ لے.پس جو لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھڑے کئے جاتے ہیں وہ اپنی کسی بات کو چھپاتے نہیں.بلکہ علی الاعلان لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے عقائد ہیں.ان باتوں پر ہمارا ایمان ہے اور یہ یہ ہماری شریعت کے احکام ہیں.اگر تمہیں ان پر کوئی اعتراض ہے تو بے شک کر لو.مگر جھوٹے لوگ اپنے مذہب اور اس کی تعلیم کو کسی نہ کسی رنگ میں ضرور چھپانے کی کوشش کرتے ہیں.پس فرماتا ہے وَ مَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطٰنٍ رَّجِيْمٍ یہ شیطان رجیم کا قول نہیں اگر شیطان رجیم کا قول ہوتا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ضرور چھپاتے مگر اُسے تو ہم نے حکم دیا ہوا ہے کہ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ (الحجر:۹۵)کہ اے نبی جس چیز کے ظاہر کرنے کا حکم دیا جاتا ہے اُسے ظاہر کرو.اور بَلِّغْ مَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ (المائدة:۶۸) کہ جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس کو تم لوگوں تک پہنچا دو.اور جب کوئی بات تم سے نہیں چھپائی جاتی تو یہ شیطان رجیم کا کلام کس طرح ہو سکتا ہے؟ تم بے شک اعتراض کر لو.اس تعلیم کے متعلق جو کچھ کہنا چاہتے ہوکھلے طور پر کہہ لو
Page 360
تمہاری ایک ایک بات کا جواب دیا جائے گا اور ثابت کیا جائے گا کہ تمہارے اعتراضات محض غلط ہیں اصل تعلیم وہی ہے جو محمد رسول اللہ صلے اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کی طرف سے پیش کی جا رہی ہے.اور جب کہ کوئی بات بھی اس کلام میں ایسی نہیں جو خدا کی طرف منسوب نہ ہو سکتی ہویا لوگوں کے اعتراضات کے ڈر سے اُسے چھپانے کی ضرورت محسوس ہو.تویہ چیز اپنی ذات میں اس بات کی دلیل ہے کہ یہ شیطان رجیم کا قول نہیں ہے.یہ صادق اور کاذب مدعی نبوت میں امتیاز کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے.عام طور پر ہر مدعی کاذب اپنی تعلیم میں کسی حد تک ضرور اخفا سے کام لیتا ہے مگر صادق مدعیٔ نبوت جو کچھ کہتا ہے علی الا علان کہتا ہے.ڈنکے کی چوٹ کہتا ہے.اور کسی اعتراض کی پروا نہیں کرتا.اسی طرح شیطانی جماعتوں میں قوتِ اقدام نہیںہوتی.کوئی ایسی سکیم اُن کے سامنے نہیں ہوتی جس پر عمل کر کے وہ ترقی کی امید کر سکیں.اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی جماعت کی ترقی کے لئے غیر معمولی سامان بھی پیدا کردیاکر تا ہے مگر بہرحال جماعتی تدابیر کا بھی بہت کچھ دخل ہوتا ہے.وہ کُنْ کہہ کر اپنے نبی کے ماننے والوں کو دنیا پر غالب نہیں کر دیا کرتا بلکہ کئی قسم کی دنیوی تدابیر سے کام لیتا ہے گویا تقدیر اور تدبیر دونوں کا ایک چکّر ہے جو چلتا چلا جاتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میںفرماتا ہے کہ وَمَکَرُوْا وَمَکَرَ اللّٰہُ وَاللّٰہُ خَیْرُ الْمَاکِــرِیْنَ (آل عمران:۵۵) کہ کفار نے بھی تدابیر سے کام لیااور اللہ نے بھی تدابیر سے کام لیااور آخر خدا پنی تدابیر میں غالب آیا.اس سے معلوم ہوتا ہے کہ الٰہی سلسلوں کی کامیابی میں بھی تدبیر کا دخل ہوتا ہے گو تدبیر اور تقدیر دونوں کی باگ ڈور خدا کے ہاتھ میںہوتی ہے اور اُسی کی مشیّت کا دنیا میںنفاذ ہوتا ہے.مگر الٰہی جماعتوں کا یہ اوّلین فرض ہوتا ہے کہ وہ ترقی کی تدابیر اختیار کریں اور ایسی سکیمیں سوچیں جو اُن کے قدم کو آگے کی طرف بڑھانے والی ہوں.ہماری جماعت کو دیکھ لو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہر فرد کے اندرایسی قوتِ اقدام رکھ دی ہے کہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ جماعت ایک دن دنیا کوکھا جائے گی.’’زمیندار‘‘ جیسے اشد معاند اخبار نے بھی ایک دفعہ لکھاتھا کہ ’’میری آنکھیں یہ دیکھ کر حیرت زدہ ہیں کہ وہ لوگ جو کینٹ اور ہیگل کے فلسفہ تک کو خاطر میں نہیں لاتے وہ بھی مرزا غلام احمد قادیانی کے ماننے والوں میں شامل ہوتے جاتے ہیں‘‘ (زمیندار ۹؍اکتوبر۱۹۳۲ء ) اُس کا یہ اقرار درحقیقت اعلان تھا اس امر کا کہ وُہ بھی محسوس کر رہا ہے کہ جماعت احمدیہ دنیا پر چھا جائے گی.پھر سچے مدعی کی تعلیم میں کوئی اخفا نہیںہوتا.وہ کھلم کھلا اپنی باتوں کو پیش کرتا اور ساری دنیا کو پکار کر کہتا ہے کہ اگر تم نے کوئی اعتراض کرنا ہے تو آئو اور اعتراض کرو مَیں اس کا جواب دینے کے لئے تیار ہوں شیطان رجیم میں یہ جرأت کہاں ہو سکتی ہے وہ تو کوشش کرتا ہے کہ لوگوں کی نگاہ سے چُھپے اور خنّاس بن کر مخفی رہے.اسی طرح سچے مدعی کی
Page 361
جماعت کو نیکی کا جو بلند مقام حاصل ہوتا ہے وہ کاذب مدعی کے ماننے والوں کو حاصل نہیں ہوتا.غرض شیطان بُزدل ہوتا ہے مگر مومنوں کے اندر اقدام پایا جاتا ہے.شیطان بدی کی طرف لے جاتا ہے اور اُن میں نیکی کا مادہ ترقی کرتا جاتا ہے.شیطان بے اصول ہوتا ہے مگر اُن کے سامنے ایک معیّن پروگرام ہوتا ہے جو اُن کی کامیابی کا ضامن ہوتا ہے.شیطان چھپ چھپ کر باتیں کرتا ہے اور وہ علی الاعلان باتیں کرتے ہیں.پھر تم کس طرح کہہ سکتے ہو کہ یہ کلام جو محمد رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں یہ شیطانِ رجیم کا کلام ہے.بعض دفعہ الفاظ تھوڑے سے ہوتے ہیں مگر اُن میں مضامین بڑے وسیع طور پر پائے جاتے ہیں یہاں بھی شیطان رجیم کا لفظ رکھ کر اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا مضمون بیان کر دیا ہے اور اُن آیات کی طرف اشارہ کر دیا ہے جن میں شیطان رجیم کا ذکر آتا ہے.اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ شیطان رجیم کی جوجو عادتیں قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں وہ سب دیکھ لو اور پھر ایک ایک بات کے متعلق غور کرو آخری تم اسی نتیجہ پر پہنچو گے کہ یہ شیطان رجیم کا کلام نہیں ہے.فَاَيْنَ تَذْهَبُوْنَؕ۰۰۲۷اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَۙ۰۰۲۸ پھر (باوجود اس کے) تم کہاں جاتے ہو.یہ تو صرف (تمام) جیالوںکے لئے ایک نصیحت ہے.حَلّ لُغَات.ذِکْرٌ ذِکْرٌ کے معنے ہیں اَلتَّلَفُّظُ بِالشَّیْءِ.کسی چیز کا زبان سے تلفّظ کرنا.إِحْضَارُہُ فِیْ الذِّھْنِ بِحَیْثُ لَا یَغِیْبُ عَنْہُ کسی چیز کو ذہن میں اس طرح مستحضر کرنا کہ وہ ذہن سے غائب نہ ہو جائے.الصِّیْتُ.شہرت.اَلشَّرَفُ.بزرگی.شرف.اَلْکِتَابُ فِیْہِ تَفْصِیْلُ الدِّیْنِ وَوَضْعُ الْمِلَلِ.ایسی کتاب جس میں دین کی تفصیل ہو.اَلذِّکْرُ مِنَ الْقَوْلِ.اَلصُّلْبُ الْمَتِیْنُ.پکی اور مضبوط بات (اقرب) تفسیر.فرماتا ہے اب بولو.کیا تمہارے لئے کوئی بھی رستہ باقی ہے.اگر تم کہو کہ اس کی ذات میں نقص ہے تو ہم نے تمہارے سامنے یہ بات پیش کر دی ہے کہ وَمَا صَاحِبُکُمْ بِمَجْنُوْنٍ.یہ تمہارا ساتھی ہے دن رات تمہارے ساتھ رہتا اور تمہارے ساتھ ہی اُٹھتا بیٹھتا ہے.تم خود اس بات کی گواہی دے سکتے ہو کہ یہ مجنون نہیں ہے.پھر اگر تم کہو کہ اس نے جوکلام پیش کیا ہے یہ خدا کی طرف سے نہیں بلکہ شیطان کی طرف سے ہے تو اس کا بھی ہم نے تفصیلًا جواب دے دیا ہے اب جواب دو کے تمہارے لئے کون سا رستہ باقی ہے سوائے اس کے اب تمہارے لئے اور کوئی
Page 362
چارہ نہیں کہ تم محمد رسول اللہ صلے اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کی طرف ہو جائو اور ان کی بیعت میں شامل ہو جائو.اگر تم محمد رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جائو گے تو جنت میں جائو گے اور اگر انکار کر و گے تو جہنم میں داخل کئے جائو گے.اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ.باقی تمہارا یہ جو سوال ہے کہ اگلے زمانہ سے تعلق رکھنے والی خبریں ابھی سے کیوں دی جا رہی ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کے مخاطب صرف مکّہ والے نہیں بلکہ وہ بھی ہیں جو تیرہ سو سال کے بعد آئیں گے اور وہ بھی ہیں جو قیامت تک آئیں گے.تم تو مکہ کے کنوئیں کے مینڈک ہو تم یہ بات کہاں سمجھ سکتے ہو کہ قرآن صرف مکہ کے لئے نہیں.صرف عرب کے لئے نہیں بلکہ وہ ساری دنیا اور قیامت تک آنے والے سب زمانوں کے لئے ہے اس لئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ باتیں بھی بیان کرنی پڑتی ہیں جو اگلے زمانوں سے تعلق رکھتی ہیں.تم ان باتوں پر ہنستے ہومگرا س کی وجہ یہی ہے کہ تمہاری نظر وسیع نہیں.تم اس حقیقت کو نہیں جانتے کہ قرآن کو ہم نے تمام دنیا کی ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے.اس لئے ضروری ہے کہ اس میں آئندہ زمانوں میں رُونما ہونے والے واقعات کے متعلق بھی خبریں موجود ہوں.لِمَنْ شَآءَ مِنْكُمْ اَنْ يَّسْتَقِيْمَؕ۰۰۲۹ (خصوصًا ) تم میں سے اس کے لئے جو سیدھے راستہ پر چلنا چاہے.تفسیر.قرآن مجید ہر فطرت کے لئے فرماتا ہے اس قرآن کی صرف یہی خوبی نہیں کہ یہ تمام زمانوں کی ہدایت کے لئے نازل کیا گیا ہے بلکہ اس کی ایک اَور خوبی یہ ہے کہ اس کے احکام میں ہر فطرت کا لحاظ رکھا گیا ہے اور ہر قسم کی فطرت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس شریعت کو نازل کیا ہے جس فطرت کا آدمی بھی اللہ تعالیٰ کے قرب کا راستہ اختیار کرنا چاہے وہ آسانی سے اختیار کر سکتا ہے اور اُسے جس قدرسامانوں کی ضرورت محسوس ہو وہ سب سامان قرآن میں موجود ہیں جس طرح تم میں سے ہر امیر اور غریب.عورت اور مرد.بچہ اور جوان.مالک اور مزدور.حاکم اور ماتحت کے متعلق قرآن کریم میں احکام موجود ہیں اور زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جس کے متعلق مکمل ہدایات اس میں نہ ہوں.اسی طرح کوئی فطرت ایسی نہیں جس کے لئے قرآنی احکام پر عمل کرنا بوجھ محسوس ہو ہر نوع کااس میں لحاظ رکھا گیا ہے ہر فطرت کا اس میں لحاظ رکھا گیا ہےاور پھر ہر زمانہ کا اس میں لحاظ رکھا گیا ہے.پس ہماری طرف سے یہ کھلا اعلان ہے کہ بنی نوع انسان میں سے جو چاہے فائدہ اُٹھا لے.لفظ مِنْکُمْ میں صرف مکہ والوں سے خطاب
Page 363
نہیں بلکہ تمام اہل زمین سے خطاب ہے اور لِمَنْ شَآءَ سے مراد لِمَنْ شَآءَ مِنْ سُکَّانِ الْعَالَمِیْنَ ہے کہ کسی زمانہ میں کسی فطرت کا آدمی آجائے قرآن میں اُس کی ہدایت کا سامان موجود ہو گا.بے شک اس میںبعض چیزیں ایسی ہیں جو تمہاری فطرت یا تمہارے زمانہ کے مطابق نہیں ہیں اور تمہیں یہ پاگل پن کی باتیں نظر آتی ہیں مگر ہم اُن کا ذکر چھوڑ نہیں سکتے کیونکہ قرآن صرف تمہارے لئے نہیں بلکہ ہر زمانہ کے لئے ہے.وَ مَا تَشَآءُوْنَ اِلَّاۤ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَؒ۰۰۳۰ اور تم یہ نہیں چاہ سکتے مگر اسی صورت میں کہ اللہ (جو) سب جہانوں کا رب (ہے) ایسا ہی چاہے.تفسیر.پہلے میں وَ مَا تَشَآءُوْنَ اِلَّاۤ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ کے صرف یہ معنے سمجھا کرتا تھاکہ وَمَا تَشَآءُ وْنَ میں وائو حالیہ ہے اور میں پچھلی آیت سے ملا کر اس کے یہ معنے کیا کرتا تھا کہ جو تم میں سے سیدھی راہ پر چلنا چاہے درآنحالیکہ اس کی مشیت خدا کی مشیت کے مطابق ہو جائے وہ ہدایت پا جائے گا لیکن اب میں اس کے ایک اور معنے سمجھتا ہوں جو ترتیبِ مضمون کے اعتبار سے بھی پہلے معنوں پر مقدّم ہیں.اس ضمن میں ایک بات پہلے ذہن نشین کر لینی چاہیے.کہ پہلے فرمایا تھا اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ اور یہاں فرمایا ہے وَ مَا تَشَآءُوْنَ اِلَّاۤ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَاِن الفاظ نے میری توجہ کو اس بات کی طرف پھیرا کہ یہاں درحقیقت ایک وسیع مضمون کی طرف اشارہ کیا گیا ہے.وہ مضمون یہ ہے کہ دنیا میں دو زمانے آیا کرتے ہیں ایک زمانہ وہ ہوتا ہے جب افراد کے سامنے ہدایت موجود ہوتی ہے یہ اور بات ہے کہ وہ اس ہدایت کی طرف توجہ کریں یا نہ کریں.لیکن دوسرا زمانہ وہ ہوتا ہے جب ہدایت کلّی طور پر دنیا سے مٹ جاتی ہے اور بحیثیت قوم دین پر زوال آجاتا ہے ایسے وقت میں افراد کے دل میں صحیح طریق کی طرف رغبت پیداہی نہیں ہوسکتی.آخر کسی چیز کی طرف رغبت اچھے نمونہ کو دیکھ کر ہوتی ہے.انسان کہتا ہے فلاں میں یہ خوبی پائی جاتی ہے مجھے بھی کوشش کرنی چاہیے کہ میرے اندر یہ خوبی پیدا ہو.فلاں بڑا نمازی ہے میں بھی نمازی بنوں یا فلاں بڑا روزہ دار ہے میں بھی روزے رکھا کروں غرض نیکیوں کی طرف رغبت اُس وقت تک پیدا نہیں ہو سکتی جب تک نمونہ سامنے موجود نہ ہو.اسی لئے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِیْنَ (التوبۃ:۱۱۹) اگر تم نیکیوں میں ترقی کرنا چاہتے ہو تو صادقین کی صحبت میں رہا کرو.لیکن جب نمونہ کوئی نہ رہے اور بحیثیت قوم
Page 364
زوالِ دین ہو جائے تو لوگ نیکیوںکی طرف کس طرح توجہ کر سکتے ہیں ایسے زمانہ میں جب تک پہلے اللہ تعالیٰ کی مشیّت ظاہر نہ ہو.وہ اپنی طرف سے کسی کو لوگوں کی اصلاح کے لئے کھڑا نہ کرے اور آسمان سے ہدایت نازل نہ ہو اس وقت تک لوگوں کے قلوب میں نیکی کی رغبت اور اس پر عمل کرنے کا احساس پیدا ہی نہیں ہو سکتا.گویا ایک وقت تو وہ ہوتا ہے جب بندے کے اختیار میں ہوتا ہے کہ وہ دین کی طرف رغبت کرے اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو یہ اس کا اپنا قصور ہوتا ہے ورنہ خدا نے اس کی ہدایت کا سامان پیدا کیا ہوا ہوتا ہے لیکن دوسرا وقت وہ ہوتا ہے کہ اگر خدا ہدایت کا سامان کرے تو لوگ ہدایت پا سکتے ہیں ورنہ صراط مستقیم کا پانا تو الگ رہا اُس کی سچی خواہش بھی لوگ اپنے دل میں پیدا نہیں کر سکتے.مامور کے آنے کی ضرورت پس ایسے زمانہ کا واحد علاج مامور کی بعثت ہوتی ہے.جب تک کسی مامور کی بعثت نہ ہو لوگ ہدایت کی راہوں کو اختیار نہیں کر سکتے یہ زمانہ جس کی ان آیات میں خبر دی جا رہی تھی چونکہ ایک مامور کا زمانہ تھا اور جس وقت یہ خبر دی جا رہی تھی وہ بھی ایک مامور کا زمانہ تھا.گویا اس سورۃ کے شروع میں جن لوگوں کی خبر دی گئی تھی وہ بھی ایسے تھے جن میں ایک مامور نے آنا تھا اور جن کی خبر آخری آیات میں ہے وہ بھی وہ تھے جن میں ایک مامور آیا ہوا تھا.اس لئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَ مَا تَشَآءُوْنَ اِلَّاۤ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنے والو! تم جو کہتے ہوکہ ہمیں محمد صلے اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں.یا اے لوگو! جنہیں ایک مامور کی بعثت کی خبر افقِ مبین میں دی گئی ہے.تم کہتے ہو کہ ہمیں مامور کی ضرورت نہیں ہم خود اللہ تعالیٰ کے قرب کے راستوں کو اختیار کر لیں گے.تمہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اس زمانہ میں ہدایت بالکل مٹ چکی ہے اس لئے تمہارا حال اب اُن لوگوں کی طرح نہیں ہے جو نبی کے زمانہ میں ہوتے ہیں جن کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ جب چاہیں ہدایت پر چلنا شروع کر دیں.تم کہتے ہو کہ ہم اپنے زور سے ترقی حاصل کر لیں گے ہمیں کسی مامور کی اتباع کی ضرورت نہیں.مگر یاد رکھو تمہارا یہ خیال بالکل غلط ہے.جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ آجائے تو پھر دنیا کی کوئی قوم ایسی نہیں ہو سکتی جو اس پر ایمان لانے کے بغیر ترقی کر سکے.اگر کوئی فرد یا کوئی قوم ایسی امید اپنے دل میں رکھے تو یہ محض اس کی جہالت ہو گی.جب دلوں میں سے کلّی طور پر ایمان مٹ جاتا ہے تو پھر جب تک خدا تعالیٰ کی طرف سے ہدایت نازل نہ ہو وہ نہ صرف ہدایت سے ہی محروم نہیں ہوتی بلکہ ہدایت کے متعلق رغبت ابھی اس کے دل میں پیدا نہیں ہو سکتی.اس لئے یاد رکھو یہ بالکل ناممکن ہے کہ تم محمد رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بغیر ترقی کر سکو.اس زمانہ میں بھی ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے مولوی مسلمانوں میں موجود ہیں اور وہ
Page 365
خیال کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو کسی مسیح یا مہدی کی کیا ضرورت ہے.علماء راہنمائی کا فرض سرانجام دینے کے لئے بالکل کافی ہیں مگر یہ بالکل غلط ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پہلےرَبُّ الْعٰلَمِيْنَ کو جوش آئے گا کہ میں اپنا کلام دنیا میں بھیجوں اس کے بعد بنی نوع انسان میں قرب الٰہی کی سچی خواہش پیدا ہو گی.اس کے بغیر یہ خواہش کبھی پیدا نہیں ہو سکتی.غرض اس آیت میں یہ اصول بتایا گیا ہے کہ جب ہدایت دنیا سے کلّی طور پر مٹ جاتی ہے گمراہی چاروں طرف چھا جاتی ہے اور خدا تعالیٰ کا نور لوگوں کی نگاہ سے اوجھل ہو جاتا ہے.اُس زمانہ میں جب بھی ترقی ہو گی آسمانی نشانات اور مامورالٰہی کی بعثت کے ذریعہ ہو گی.گویا پہلے خدا کی مشیّت آسمان سے ظاہر ہو گی اور اس کے بعد لوگوں کے دلوں میں نیکی کی طرف رغبت پیدا ہو گی اسی لئے ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ کووَ مَا تَشَآءُوْنَ اِلَّاۤ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ کے ساتھ ملا کر بیان کیا کہ ایک ایسا زمانہ ہوتا ہے رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ جب ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ نازل کرے تب ہی افراد کے دلوں میں نیکی کی خواہش پیدا ہوتی ہے ورنہ نہیں.جو شخص اس نکتہ سے غافل ہوتا ہے وہ ہدایت پانے سے محروم رہ جاتا ہے.خ خ خ خ
Page 366
سُوْرَۃُ الْاِنْفِطَارِ مَکِّیَّۃٌ سورۃ انفطار.یہ سورۃ مکی ہے وَھِیَ دُوْنَ البَسْمَلَةِ تِسْعُ عَشَرَةَ اٰیَةً اور اس کی بسم اللہ کے علاوہ اُنیس ۱۹ آیات ہیں.سورۃ الانفطار کا تعلق پہلی سورۃ سے سُورۃ الانفطار کا مضمون پہلی سورۃ کے مضمون کےتسلسل میں ہے اسے الگ اس لئے کیا گیا ہے کہ اس میں اسی سلسلہ کی ایک مستقل کڑی کو بیان کیا گیا ہے.گویا مضمون تو وہی ہے مگر اُس کی ایک دوسری قسم بیان کی گئی ہے اور وہ یہ ہے کہ ایسی علامتیں جو مسیحیت کے ساتھ خاص ہیں وہ اس جگہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں.اِس بات کی حکمت کہ کیوں دو ٹکڑے کر دئے گئے ہیں ایک تو یہی ہے کہ بعض حصّے بعض مضمونوں کے خاص ہوتے ہیں اُن پر زور دینے کے لئے اُن کو الگ کر دیا جاتا ہے.قرآن مجید کی ایک خصوصیت دوسری حکمت جو قرآن کریم کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے اور گووہ ایک چھوٹی سی بات ہے مگر اس سے قرآن کریم کے ماننے والوں کو بہت فائدہ پہنچاہے یہ ہے کہ قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ تھا اور قرآن کریم آخری الہامی کتاب تھی جس کی وجہ سے اس کے مضامین کو اس کے ماننے والوں کے قلوب میں پختہ کرنا نہایت ہی اہم سوال تھا پہلی کتابوں کو اگر اُن کے ماننے والے بُھول بھی جاتے تو اس میں کوئی حرج نہ تھا.کیونکہ اُن کی جگہ اور کتابیں آنے والی تھیں لیکن قرآن کریم آخری شرعی کتاب تھی اگر لوگ اس کو بھول جاتے تو دُنیا میں تباہی آ جاتی.اور لوگ ہمیشہ کی گمراہی میں مبتلا ہو جاتے.قرآن کریم کو مختلف ٹکڑوں میں اتارے جانے کی وجہ پس اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی تدبیر اختیار کی جو بظاہر بالکل چھوٹی سی ہے مگر نتیجہ کے لحاظ سے اتنی اہم ہے کہ اُس کی قیمت کا کوئی اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا.اور وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کو مختلف ٹکڑوں میں بیان کیا گیا.اور پھر وہ ٹکڑے ایسی ترتیب سے بنائے گئے کہ چھوٹے سےچھوٹے ٹکڑہ سے لے کر بڑے سے بڑے ٹکڑہ تک اس کو تقسیم کر دیا گیا جس کی وجہ سے چھوٹا بچہ بھی اُس کا کچھ حصہ یاد کر سکتا ہے اُس سے بڑا بھی یاد کر سکتا ہے اُس سے بڑا بھی اور اُس سے بڑا بھی.ادنیٰ سے ادنیٰ حافظہ والا بھی اس کا کچھ حصہ یاد کر سکتا ہے اور پھر اس سے اوپر جیسے جیسے حافظے بڑھتے چلے جائیں وہ اس کے مختلف ٹکڑے
Page 367
یاد کر سکتے ہیں.سورۃ اخلاص اور سورہ کوثر کتنی چھوٹی چھوٹی سورتیں ہیں پوری دودو سطر کی بھی نہیں ہیں بلکہ اگر باریک لکھی جائیں تو ایک سطر میں ختم ہو جاتی ہیں اور معمولی حافظہ کا چار سال کا بچہ بھی اُس کو یاد کر سکتا ہے.سورۂ بقرہ اڑھائی پاروں کی ہے اور ان کے درمیان مختلف درجوں کی سورتیں ہیں کوئی تین پانچ دس یا پندرہ آیت کی.کوئی بیس تیس اور ساٹھ آیت کی اور کوئی سو آیت کی.اِسی طرح سورتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں پس کسی لیاقت اور حافظہ کا آدمی نہیںجو قرآن کریم کی کوئی سورۃ یاد نہ کر سکتا ہو.اور جس کا حافظہ تیز ہو وہ تو سارا قرآن یاد کر لیتا ہے چنانچہ اس پر عمل ہو رہا ہے اور وہ مسلمان جو تعلیم یافتہ ہیں آخری دو تین پاروں کی سورتیں علیٰ قدر مراتب یاد کر لیتے ہیں.اِس طرح ایک ہی وقت میں قرآن کریم کے مختلف ٹکڑوں کے لاکھوں حافظ موجود ہوتے ہیں سارے قرآن کے حافظ الگ رہے.بظاہر یہ کتنی چھوٹی سی بات ہے مگر دنیا کی زندگی چھ ہزار سال کی سمجھو یا لاکھ کی یا دس لاکھ کی.اگر کسی انسان نے یہ بات بنائی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی انسان کو یہ بات نہیں سوجھی آخر دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں یا تو قرآن مجید کو انسانی کلام سمجھا جائے یا خدا ئی کلام سمجھا جائے.اگر کہو کہ یہ انسانی کلام ہے تو پھر دنیا میں جو انسانی کلام ہیں ان میں سے کسی میں بھی یہ بات نہیں اور آج تک کسی انسان کو یہ بات نہیں سوجھی بلکہ قرآن کریم کے نازل ہونے کے بعد بھی نہیں سوجھی.اور اگر یہ خدا تعالیٰ کا کلام ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ اس کتاب کے متعلق اس کا منشا تھا کہ اسے یاد کیا جائے تبھی اُس نے یہ تدبیر کی.اگر انسانی کلام سمجھ لو تب بھی اس کی فوقیت ثابت ہے اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ ایک چھوٹے سے گُر کے ذریعہ اُس نے کایا پلٹ دی.اور اگر خدائی کلام سمجھ لو توتب بھی ماننا پڑے گا کہ خدا تعالیٰ اس کو محفوظ رکھنا چاہتا تھا.قرآن مجید کا مختلف ٹکڑوں میں اترنا اس کی فوقیت کا موجب اگر کوئی کہے کہ کوئی ٹکڑہ تو جس کتاب میں سے چاہے انسان یاد کر سکتا ہے پس اس طرح ٹکڑے کرنے سے قرآن کریم کو کون سی خصوصیت حاصل ہو گئی تو اس کا جواب یہ ہے کہ بیشک کتاب میں سے کوئی ٹکڑہ انسان یاد کر سکتا ہے مگر کیا ہر شخص اس بات کا بھی فیصلہ کر سکتا ہے کہ وہ ٹکڑہ اپنے اندر کامل مضمون رکھتا ہے.یہ تو مصنّفِ کتاب یا منزلِ کتاب ہی بتا سکتا ہے کہ اُس کا کون کون سا ٹکڑہ اپنی ذات میں مکمّل ہے قرآن شریف کا ہر ٹکڑہ صرف چند آیتوں کا نام نہیں بلکہ ایک مکمّل مضمون کا نام ہے کوئی تین آیتیں سورہ بقرہ کی انسان یاد کر لے تو اسے کیا فائدہ ہو سکتا ہے بسا اوقات وہ تین آیتیں کسی مکمّل مضمون پر مشتمل نہ ہوں گی اور جب تک سیاق و سباق کو نہ ملایا جائے گا وہ اپنے مفہوم کو واضح نہیں کریں گی لیکن سورۂ اخلاص کو لے لو تو گو وہ دو سطر کی بھی سورۃنہیں مگر اُس میں ایک سارا مضمون بیان کر دیا گیا ہے اسی طرح سورۂ کوثر لے لو یا سورۂ لہب کو
Page 368
لے لو سب اپنے اپنے مضامین کے اعتبار سے بالکل مکمّل ہیں لیکن اور سورتوں کا اگر اتنا ہی کوئی ٹکڑہ لے لیا جائے تو جہاں تک مضمون کا تعلق ہے ضروری نہیں کہ اُس میں مکمّل مضمون آجائے مگر جب مصنف یا منزلِ کتاب ٹکڑوں کو الگ الگ کر دے تو پھر اس میں سہولت ہو جاتی ہے پس قرآن کا صرف کوئی ٹکڑہ یاد کر لینا وہ فائدہ نہیں دے سکتا تھا جو فائدہ موجودہ صورت میں پہنچ رہا ہے اور وہ تحریک بھی پیدا نہیں کر سکتا تھا جو موجودہ صورت میں قلوب میں پیدا ہوتی ہے چنانچہ اس بات کا یہ نتیجہ ہے کہ اگر عیسائیوں سے پوچھا جائے کہ انہیں انجیل کے کتنے ٹکڑے یاد ہیں تو شائد چند معروف ٹکڑے انہیں یاد ہوں تو ہوں ورنہ ساری انجیل مختلف ٹکڑوں کی صورت میں ان کو یاد نہیں ہو گی.لیکن اگر قرآن کے متعلق پوچھا جائے تو سارا قرآن مختلف ٹکڑوں کی صورت میں غیر حافظ لوگوں کو بھی یاد ہو گا.کسی کو سورۃ بقرہ یاد ہو گی کسی کو سورۂ آل عمران یاد ہو گی کسی کو سورۂ نساء یاد ہوگی اور کسی کو آخری سورتوں میں سے کوئی سورتیں یاد ہوں گی تو علیحدہ تقسیم کی وجہ سے حفظ میں جو مدد ملی ہے وہ اکٹھا لکھنے کی صورت میں نہیں مل سکتی تھی اور اسی حکمت کے ماتحت ان کی تقسیم کی گئی ہے.غرض گو اس سورۃ کا مضمون پہلی سورۃ کے مضمون کے تسلسل میں ہے مگر اسے الگ اس لئے کیا گیا ہے کہ اس میں بعض جدید مضامین کی طرف توجہ دلائی گئی جو گو تعلق تو اسی سلسلہ سے رکھتے ہیں مگر ان کی نوعیت اور رنگ کی ہے اور جیسا کہ مَیں نے بتایا ہے قرآن کریم کی یہ خصوصیت ہے کہ مضمون جہاں مختلف ہوتا ہے وہاں الگ سورۃ بنا دی جاتی ہے تاکہ اس کا پڑھنا اور یاد کرنا کمزوروں پر بھی گراں نہ گزرے.بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۰۰۱ (میں)اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا (اور) بار بار رحم کرنے والا ہے (شروع کرتا ہوں) اِذَا السَّمَآءُ انْفَطَرَتْۙ۰۰۲ جب آسمان پھٹ جائے گا.حَلّ لُغَات.اِنْفَطَرَتْ اِنْفَطَرَتْ اِنْفَطَرَ سے مؤنث کا صیغہ ہے اور اِنْفَطَرَ الشَّیْئُ کے معنے ہیں اِنْشَقَّ کوئی چیز پھٹ گئی (اقرب) پس اِذَا السَّمَآءُ انْفَطَرَتْ کے معنے ہوں گے جب آسمان پھٹ جائے گا.تفسیر.اِذَا السَّمَآءُ انْفَطَرَتْمیں عیسائیت کے تمام دنیا میں چھا جانے کی طرف اشارہ اِذَا السَّمَآءُ انْفَطَرَتْ میں آخری زمانہ کے اُس تغیر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو عیسائیت سے وابستہ ہے یعنی عیسائیت
Page 369
کے غلبہ کی طرف اس سورۃ میں اشارہ کیا گیا ہے.سورۂ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تَكَادُ السَّمٰوٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَ تَنْشَقُّ الْاَرْضُ وَ تَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا.اَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمٰنِ وَلَدًا (مریم :۹۱،۹۲)قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیںاور زمین بھی پھٹ جائے اور پہاڑ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر جائیں.اس وجہ سے کہ ان لوگوںنے رحمٰن کا ایک بیٹا تسلیم کیا ہے جس وقت قرآن کریم نازل ہوا ہے اس وقت عیسائیت کو دنیا کے بہت تھوڑے حصہ پر غلبہ حاصل تھا اور وہ عام تبلیغ بھی نہیں کرتے تھے اُس وقت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جتنا شرک عیسائیوں کی طرف سے اس وقت کیا جاتا ہے قریب ہے کہ اس سے آسمان پھٹ جائیں پھر اگر کوئی ایسا زمانہ آجائے جب اُس سے دس بیس بلکہ سو گُنا زیادہ شرک پھیل جائے تو لازمی طور پر قرآنی محاورہ کے مطابق ہم یہی کہیں گے کہ آسمان پھٹ گیا چنانچہ دیکھ لو روما کی حکومت عیسائی تھی مگر ساری دُنیا اُس کے ماتحت نہیںتھی صرف ترکی.مصر.حبشہ اور یونان اس کے ماتحت تھا گویا وسطی ایشیا کا ایک جزو تھا جس پر وہ حکمرانی کر رہی تھی مگر آج عیسائیت کو ساری دنیا پر غلبہ حاصل ہو چکا ہے.پھر عیسائیت کی تبلیغ کے لئے جن تدابیر کو اس زمانہ میں اختیار کیا گیا ہے وہ پہلے کبھی اختیار نہیں کی گئیںکروڑوں کروڑ انجیل کے نسخے دُنیا کے کونے کونے میںپھیلا دئے گئے ہیں.لاکھوں روپیہ اپنے مشنوں کی کامیابی پر خرچ کیا جاتا ہے مدرسے بنائے جاتے ہیں تاکہ اُن کے ذریعہ لڑکوں کو عیسائیت کا شکار بنایا جا سکے.کالج بنائے جا رہے ہیں تاکہ عیسائیت کا زہر نوجوانوں کے قلوب میں داخل کیا جائے، کوڑھی خانے بنائے جا رہے ہیں.شفاخانے تیار ہو رہے ہیں اور ان سب کی غرض صرف یہی ہے کہ لوگ ایک خدا کی پرستش چھوڑ دیں اور تین خدائوں کو ماننے لگ جائیں پس جب عیسائیت کے قلیل غلبہ کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں کیونکہ یہ لوگ مسیح ؑ کو خدا کا بیٹا قرار دے رہے ہیںتو اب جبکہ شرک تمام دنیا میںپھیل چکا ہے اور عیسائیت کا غلبہ اپنے کمال تک جا پہنچا ہے یہ کیوںنہیں کہا جائے گا کہ وہ آسمان جو پھٹنے کے قریب تھا اب شدّت شرک کی وجہ سے پھٹ گیا ہے.جو چیز اپنی انتہاء کو پہنچ چکی ہو اس پر اگر ذرا بھی زور لگ جائے گا تو وہ سلامت نہیں رہ سکتی بلکہ پھٹ جاتی ہے.پس فرماتا ہے اِذَا السَّمَآءُ انْفَطَرَتْ وہ جو ہم نے کہا تھا کہ آسمان اور زمین عیسائیوں کے مشرکانہ عقیدہ کی وجہ سے پھٹنے کے قریب ہیں اگر شرک ذرا بھی بڑھا تو وہ پھٹ جائیں گے وہ زمانہ آئندہ آنے والا ہے کہ اَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمٰنِ وَلَدًا پر یہ لوگ زور دینا شروع کر دیں گے اور آسمان پھٹ جائے گا کیونکہ ظلم اپنی انتہاء کو پہنچ جائے گا پس آسمان پھٹ جائے گا سے مراد یہ ہے کہ عیسائیت غالب آجائے گی اور شرک بڑی کثرت سے دنیا میں پھیل جائے گا.اسلام کی ترقی اور عیسائیت کی ترقی میں ایک فرق چنانچہ حقیقت یہ ہے کہ جس قسم کی ترقی اورجس قسم کا
Page 370
غلبہ عیسائیت کو حاصل ہو ا ہے اس قسم کی ترقی اور غلبہ کی مثال درحقیقت اسلام کے زمانہ میں بھی نہیں ملتی.فرق یہ ہے کہ اسلام نے ایک چھلانگ میں ترقی کی ہے اور انہوں نے بیسیوں چھلانگوں میں ترقی کی ہے پھر اسلام کی ترقی تو معجزانہ تھی مگر ان کی سب ترقیات غیر معجزانہ ہیں لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جہاں تک مادیات کا سوال ہے اسلام کے غلبہ سے یہ غلبہ بڑھ گیا ہے کیونکہ اسلام اپنے ہر ماننے والے کو انصاف سکھاتا ہے اور وہ ظلم اور بے انصافی کے قریب بھی نہیں پھٹکتا.مگر یہ لوگ وہ ہیں جو نہ انصاف کی پروا کرتے ہیں نہ ظلم سے ڈرتے ہیں نہ حقوق غصب کرنے سے گھبراتے ہیں.مغرب سے مشرق کے انتہائی کناروں تک یہ لوگ پھیلتے چلے گئے اور مسیح ؑ کی عظمت دلوں میں قائم کرتے گئے.یہ اثر لوگوں کے قلوب پر اس حد تک ہے کہ عیسائیوں میں ایسے کئی لوگ مل جائیں گے جو تین خدائوں کے قائل نہیں ہوں گے مگر مسیح ناصریؑ کی عظمت اُن کے دلوں میں برابر قائم ہو گی مجھے ایک دفعہ انگلستان میں ایک دہریہ ڈاکٹر ملنے کے لئے آیا اور مَیں نے دیکھا کہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد وہ رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیتا.مَیں نے اسے سمجھایا کہ یہ طریق درست نہیں رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم پر تمہیں حملہ نہیں کرنا چاہیے مگر وہ آریوں کی طرح برابر رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حملے کرتا چلا گیا.آخر جب مَیں نے دیکھا کہ وہ میرے صبر سے ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے اور رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حملہ کرنے میں بڑھ رہا ہے تو مَیں نے یسُوع کی حقیقت اس کے سامنے کھولنی شروع کر دی.ابھی مَیں نے چند ہی باتیں کی تھیں کہ اس کا رنگ سُرخ ہو گیا اور کہنے لگا.آپ مسیح ؑ کا ذکر کیوں کرتے ہیں مَیں نے کہا مَیں سمجھ گیا ہوں کہ گو تم دہریہ ہو مگر تمہارے دل میں عیسائیت باقی ہے اس لئے میں مسیح ؑ کا ضرور ذکر کروں گا.وہ کہنے لگا مَیں مسیح ؑکے خلاف کوئی بات نہیں سُن سکتا.مَیں نے کہا تو میں رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بات نہیں سُن سکتا.اگر تم رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم پر حملہ جاری رکھو گے تو تمہیں مسیح ؑ کے خلاف بھی میری زبان سے باتیں سننی پڑیں گی اس پر غصہ میں اس نے بات بند کر دی اور چلا گیا تو مَیں نے دیکھا ہے بعض لوگ اس بات پر خوش ہو جاتے ہیں کہ یورپ میں دہریت پائی جاتی ہے جو اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ لوگ عیسائیت سے بیزار ہو چکے ہیں حالانکہ دہریہ ہونے کے باوجود اُن کے دلوں سے مسیح ناصریؑ کی عظمت نہیں گئی.یہی رگ تھی جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے پکڑی اور جس کی وجہ سے مسلمانوں نے آپ پر کفر کے فتوے لگانے شروع کر دئے آپ نے فرمایا جب تک مسیح ؑ کو دفن نہیں کیا جائے گا عیسائیت کبھی مر نہیں سکتی.(ازالہ اوہام روحانی خزائن جلد ۳ صفحہ ۴۰۲)یہ صرف مسیح ؑ کے پرستار ہیں اور عقائد سے ان کا کوئی واسطہ نہیں.تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِذَا السَّمَآءُ انْفَطَرَتْ آسمان پھٹ جائے گا.آسمان پھٹ جانے کے معنے یہ ہیں کہ بڑی
Page 371
سخت آفت آ جائے گی اور اتنا شدید ظلم ہو گا کہ اس سے بڑا ظلم اور کوئی نہیں ہو سکتا.آسمان کے پھٹنے سے مراد آسمانی لوگوں کے دلوں کا زخمی ہونا آسمان پھٹ جانے کے یہ معنے بھی ہو سکتے ہیں کہ آسمانی وجودوں کے دل اس شرک کو دیکھ کر زخمی ہو جائیں گے.خدا تعالیٰ کو یہ بات سخت بُری لگے گی فرشتوں کو اس سے تکلیف ہو گی اور انبیاء کے دل اس کو دیکھ کر تڑپ اٹھیں گے.چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسَّلام نے لکھا بھی ہے کہ مَیں نے حضرت مسیح ؑ کو کشفی حالت میں دیکھا کہ وہ اس تکلیف سے تڑپ رہے ہیں کہ میرے نام پر دُنیا میں اس طرح ظلم ہو رہا ہے.(نور الحق روحانی خزائن جلد ۸ صفحہ ۵۶،۵۷) غرض اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ عیسائیت کا غلبہ ہو جائے گا اور آسمان پر جوش پیدا ہو جائے گا کہ دُنیا پر اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے جس کی مثال اور کہیں نہیں ملتی گویا یہ ایک ایسی آفت ہو گی جو بے مثال ہو گی.حضرت خلیفۂ اوّلؓ کسی بزرگ کا ایک ذوقی لطیفہ سُنایا کرتے تھے کہ انہوں نے کہا کہ ضَآلِّیْن پر جوشدّ اور مدّ اکٹھی ہیں اِس سے معلوم ہوتا ہے کہ عیسائی فتنہ بڑا سخت ہو گا.اور پھر بڑا لمبا ہو گا.وَ اِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْۙ۰۰۳ اور جب ستارے جھڑ جائیں گے.حَلّ لُغَات.کَوَاکِبُ.کَوَاکِبُ کَوْکَبٌ کی جمع ہے.اور جب کَوْکَبَ الْحَدِیْدُ کہیں تو اس کے معنی ہوتے ہیں بَرِقَ وَتَوَقَّدَ یعنی لوہا آگ میںگرم کرنے پر سُرخ ہو گیا.اور چمکنے لگ پڑا.کَوْکَبٌ کا لفظ اپنے اندر کثیر معنے رکھتا ہے جو یہ ہیں:.(۱)اَلنَّجْمُ.ستارہ (۲)نُقْطَۃٌ بَیْضَائُ تَحْدُثُ فِی الْعَیْنِ.آنکھ کا پھولا.(۳)مَا طَالَ مِنَ النَّبَاتِ.جو روئیدگی لمبے قد کی ہو.اس کوبھی کوکب کہتے ہیں.(۴)سَیِّدُ الْقَوْمِ وَفَارِسُھُمْ.قوم کا سردار اور ان کا جرنیل.(۵)شِدَّۃُ الْـحَرِّ.گرمی کی شدّت.(۶)اَلسَّیْفُ.تلوار (۷) اَلْمَائُ.پانی (۸) اَلْمَجْلِسُ.مجلس کو بھی کوکب کہتے ہیں جہاں لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے.(۹)اَلْمِسْمَارُ.کیل کو بھی کوکب کہتے ہیں (۱۰)اَلخِطَّۃُ یُخَالِفُ لَوْنُھَا لَوْنَ اَرْضِھَا.کوکب اس زمین کو بھی کہتے ہیں جس کا رنگ پاس کی زمینوں سے مختلف ہو (۱۱) اَلطَّلْقُ مِنَ الْاَوْدِیَۃِ.وسیع وادی کو بھی کوکب کہتے ہیں (۱۲)الرَجُلُ بِسِلَاحِہِ.مسلّح آدمی کو بھی کوکب کہتے ہیں (۱۳) اَلْجَبَلُ.پہاڑ کو بھی کہتے ہیں.(۱۴)اَلْغُلَامُ
Page 372
کَوْکَبٌ کا لفظ اپنے اندر کثیر معنے رکھتا ہے جو یہ ہیں:.(۱)اَلنَّجْمُ.ستارہ (۲)نُقْطَۃٌ بَیْضَائُ تَحْدُثُ فِی الْعَیْنِ.آنکھ کا پھولا.(۳)مَا طَالَ مِنَ النَّبَاتِ.جو روئیدگی لمبے قد کی ہو.اس کوبھی کوکب کہتے ہیں.(۴)سَیِّدُ الْقَوْمِ وَفَارِسُھُمْ.قوم کا سردار اور ان کا جرنیل.(۵)شِدَّۃُ الْـحَرِّ.گرمی کی شدّت.(۶)اَلسَّیْفُ.تلوار (۷) اَلْمَائُ.پانی (۸) اَلْمَجْلِسُ.مجلس کو بھی کوکب کہتے ہیں جہاں لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے.(۹)اَلْمِسْمَارُ.کیل کو بھی کوکب کہتے ہیں (۱۰)اَلخِطَّۃُ یُخَالِفُ لَوْنُھَا لَوْنَ اَرْضِھَا.کوکب اس زمین کو بھی کہتے ہیں جس کا رنگ پاس کی زمینوں سے مختلف ہو (۱۱) اَلطَّلْقُ مِنَ الْاَوْدِیَۃِ.وسیع وادی کو بھی کوکب کہتے ہیں (۱۲)الرَجُلُ بِسِلَاحِہِ.مسلّح آدمی کو بھی کوکب کہتے ہیں (۱۳) اَلْجَبَلُ.پہاڑ کو بھی کہتے ہیں.(۱۴)اَلْغُلَامُ الْمُرَاھِقُ اُس لڑکے کو بھی کوکب کہتے ہیں جو جوانی کے قریب پہنچا ہوا ہو (۱۵) اَلْفُطْرُ کھمبی کو بھی کوکب کہتے ہیں (۱۶) مُعْظَمُ الشَّیْءِ کسی چیز کے بڑے حصے کو بھی کوکب کہتے ہیں.(۱۷) نُوْرُ الرَّوْضَۃِ باغ کی کلی کو بھی کوکب کہتے ہیں (۱۸)بَرِیْقُ الْحَدِیْدِ وَتَوَقَّدُہ.گرم ہو کر جو لوہے میں چمک پیدا ہوتی ہے اسے بھی کوکب کہتے ہیں (۱۹) کَوْکَبٌ مِنَ الْبِئْرِ عَیْنُھَا الَّذِیْ یَنْبَعُ الْمَائُ مِنْہُ.کنوئیں کے سوتے کو بھی کوکب کہتے ہیں جس میں سے پانی نکلتا ہے (۲۰)کہر کو بھی کوکب کہتے ہیں.نیز عربی زبان کا محاورہ ہے ذَھَبُوْا تَحْتَ کُلِّ کَوْکَبٍ جس کے معنے ہیں تَفَرَّقُوْا.وہ الگ الگ ہو گئے (۲۱) یَوْمٌ ذُوْ کَوَاکِبَ کے معنے ہوتے ہیں ذُوْ شَدَائِدَ یعنی ایسا دن جو بلائوں اور مصیبتوں سے پُر ہو (اقرب) غرض کَوْکَب کے وسیع معنے ہیں.کوکب ستاروں کو بھی کہتے ہیںسردارانِ قوم کو بھی کہتے ہیں اور قوم کے جرنیل کو بھی کہتے ہیں.اِنْثَتَرَتْ.اِنْثَتَرَتْ نَثَـرَ سے ہے اور نَثَـرَ الشَّیْئَ کے معنے ہوتے ہیں رَمَاہُ مُتَفَرِّقًا اُس نے کسی چیز کو اس طرح پھینکا کہ وہ بکھر گئی اور تَنَاثَرَ وَتَنَثَّرَ وَانْتَثَرَ الشَّیْئُ کے معنے ہوتے ہیں.تَسَاقَطَ مُتَفَرِّقًا کوئی چیز متفرق ہو کر گر گئی.عرب کہتے ہیں.تَفَرَّقَ الْقَوْمُ وَتَنَثَّرُوا.یعنی قوم منتشر ہو گئی اور بکھر گئی (اقرب) تفسیر.اِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْاوراِذَا النُّجُوْمُ انْكَدَرَتْ ہر دو آیات کے مضمون میں ایک فرق اس جگہ یہ امر ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ اس سے پہلی سورۃمیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَاِذَاالنُّجُوْمُ انْکَدَرَتْاور یہاں فرمایا ہے وَاِذَاالْکَوَاکِبُ انْتَثَرَتْ درحقیقت یہ دو الگ الگ باتیں ہیں جو ایک خاص فرق کی طرف توجہ دلاتی ہیں.اسی لئے وہاں نـجُوم کا لفظ رکھا گیا تھا اور یہاں کواکب کا لفظ رکھا گیا ہے.پھر وہاں انکدار کا لفظ رکھا گیا تھا اور یہاں اِنْتِثَار کا لفظ رکھا گیا ہے.اس میں کوئی شبہ نہیں کہ انکدار کے معنے بھی انتثار کے ہی ہوتے ہیں مگر یہاں الفاظ اللہ تعالیٰ نے بدل دیئے ہیں.حالانکہ لفظوں کا بدلنا ضروری نہیںقرآن کریم میں ایک ایک آیت تین تین چار چار جگہوں میں آئی ہے.پس یہ نہیں کہ قرآن کریم نے یہ اصول مقرر کیا ہوا ہو کہ جب وہ دوسری دفعہ وہی مضمون بیان کرے تو الفاظ کو ضرور بدل دیتا ہے.ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم الفاظ کو دہرا بھی دیتاہے اس لئے ان آیات میں الفاظ کے بدلنے میں ضرور کوئی حکمت ہونی چاہیے اگر انکدار کا لفظ اِنْتِثَار کے معنوں میں واقعہ ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ اِنْکَدَرَتْ کی بجائے اِنْتَثَـرَتْ بھی کہہ سکتا تھا اور اگر یہاں انتثار بمعنے انکدار ہے تو یہاں انتثرت کی بجائے انکدرت بھی کہا جا سکتا تھا.کیونکہ قرآن کریم میں کئی آیتیں ایسی موجود ہیں جن میں ایک ہی مضمون بیان کرنے کے لئے پہلے ہی الفاظ کو دُہرایا گیا ہے پس قرآن کریم کے اس طریق عمل کو دیکھتے ہوئے کہ وہ الفاظ کے دُہرانے سے اجتناب کرنے کو ضروری نہیں سمجھتا یہاں الفاظ کا بدل دینا بتا رہا ہے کہ ان دونوںکے مفہوم میں کوئی فرق ہے.
Page 373
الفاظ کے دُہرانے سے اجتناب کرنے کو ضروری نہیں سمجھتا یہاں الفاظ کا بدل دینا بتا رہا ہے کہ ان دونوںکے مفہوم میں کوئی فرق ہے.نجم اور کوکب کے معنے میں فرق اس تمہید کے بعد میں یہ بتاتا ہوں کہ نجم کی تشریحات کو جب ہم لغت میں دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا زور اصل کے معنوں پر ہوتا ہے چنانچہ نجمؔ کے ایک معنے یہ بتائے جا چکے ہیں کہ جس کی ساق نہ ہواور یہ لازمی بات ہے کہ جس چیز کی ساق نہ ہو گی وہ لمبی نہیں ہو سکے گی.وہ پودہ جس کی جڑ نہ ہو وہ اونچا کس طرح ہو سکتا ہے مگر کوکب کے ایک معنے لغت میں یہ لکھے ہیں کہ مَاطَالَ مِنَ النَّبَاتِ وہ روئیدگی جو لمبے قد کی ہو.پھر کوکب کے ایک معنے سَیِّدُ الْقَوْمِ وَفَارِسُھُمْ کے کئے گئے ہیں گویا اس میں فن اور مہارت کی طرف اشارہ ہے کیونکہ فارِس جرنیل کو کہتے ہیں پس نجم میں ہنر کی طرف نہیں بلکہ نسل کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور کوکب میں نسل کی طرف اتنا اشارہ نہیں پایا جاتا جتنا ہنر کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے.اِدھر کوکب کے ایک معنے شِدَّۃُ الْحَرِّ کے بھی ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کواکب سے مراد ایسے لوگ ہوتے ہیں جن میں کام کرنے کا مادہ زیادہ پایا جاتا ہے اُن کی طبیعت میںتیزی ہوتی ہے اوروہ سیف ماضی کے طور پر قوم میں اثر اور رسوخ رکھتے ہیں.یہ فرق بتا رہا ہے کہ پہلی آیت اور نجوم اور اِس آیت میںکواکب اور اسی طرح پہلی آیت میں انکدرت اور اس آیت میں انتثرت کے الفاظ کا استعمال بلا وجہ نہیں بلکہ ان میں بہت بڑی حکمت پائی جاتی ہے.انکدار اور انتثار کے معنے میں فرق اصل بات یہ ہے کہ انکدار کے معنے گدلا ہو جانے کے ہیں اور انتثار کے معنے ٹوٹ کر متفرق ہوجانے کے ہیں پس سورۂ تکویر کی آیت وَاِذَا النُّجُوْمُ انْكَدَرَتْ میں اس طرف اشارہ کیا گیا تھا کہ نسلی رئوسا کا پبلک میں رسوخ کمزور ہو جائے گا اور وَاِذَاالْکَوَاکِبُ انْتَثَرَتْ میں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ صاحبِ فن اور ہنر لوگ بھی محض اپنے فن اور ہنر کےزورسے وہ رسوخ جو پہلے پیدا کر لیا کرتے تھے نہ کر سکیں گے یعنے یورپ کی ترقی کے سلسلہ میں جو تغیّرات پیدا ہوں گے اُن کے نتیجہ میں بڑے بڑے ماہرین فن کی طاقتیں بالکل ٹوٹ جائیں گی چنانچہ دیکھ لو یہ دونوں باتیں اس زمانہ میں پوری ہو گئی ہیں غیر عیسائی ممالک میں علماء تو موجود ہیں مگر ان کا رسوخ زائل ہو چکا ہے یا بڑے بڑے فنکار تو پائے جاتے ہیں مگر اُن کا اثر باقی نہیںرہا اور عیسائی ممالک میں اِن تغیّرات کی وجہ سے پارلیمنٹیں بن گئی ہیں.اُمراء اور رئوسا کی طاقتیں بالکل ٹوٹ گئی ہیں اور امراء اور ماہرین فنوں کی جگہ لیبر پارٹیوں اور کمیونسٹ پارٹیوں وغیرہ نے لے لی ہے پس یہ علامت بھی اس تغیّر پر دلالت کرتی ہے جو یورپ کی ترقی کے سلسلہ میں ظاہر ہوا ہے.غیر عیسائی ممالک میں بھی یوروپین ممالک کی نقل میں یہ تغیر
Page 374
پیدا ہو رہا ہے مگر وہ کامل نہیں اس جگہ چونکہ یوروپین اقوام کا ذکر ہے اس لئے فرماتا ہے کہ یوروپین قوموںمیں جو تغیّر پیدا ہو گا وہ ایسا ہو گا کہ قوم پر اثر رکھنے والے لوگ خواہ نسلی سردار ہوں یا فنّی سردار ہوں بالکل گر جائیں گے اور دوسری قومیں اُن کی جگہ لے لیں گی لیکن غیر اقوام میں یہ تغیّر پیدا ہو گا کہ اُن میں صرف بڑے لوگوں کا رسوخ کمزور ہو جائے گا.وَ اِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْۙ۰۰۴ اور جب سمندر پھاڑ (کرملا )دیئے جائیں گے.حَلّ لُغَات.فُـجِّرَتْ فُـجِّرَتْ فَـجَّرَ سے مجہول کا مؤنث کا صیغہ ہے اور فَـجَّرَ کے معنے وہی ہیں جو فَـجَرَ کے ہیں اور اِن دونوں میں سوائے اس کے اور کوئی فرق نہیں کہ فُـجِّرَ میں تشدید مبالغہ کے لئے استعمال کی جاتی ہےورنہ فَـجَرَ بھی متعدی ہے اور فَـجَّرَ بھی متعدی ہے فَـجَرَ الْمَائَ کے معنے ہوتے ہیں فَتَحَ لَہٗ طَرِیْقًا فَجَرٰی اس نے پانی کے لئے راستہ کھولا اور وہ بہنے لگ گیا اور فجر الْقَنَاۃَ کے معنے ہوتے ہیں شَقَّھَا وَقِیْلَ شَقًّا وَاسِعًا پانی کی نالی کو خوب کھلا بنایا اور جب فَـجَّرَ الرَّجُلُ کہیں تو اس کے معنی ہوں گے اَنْسَبَہٗ اِلَی الْفَجُوْرِ اُس کو فجور کی طرف منسوب کیا.(اقرب) تفسیر.اِس آیت کے الفاظ بھی قریبًا وہی ہیں جو پہلی سورۃ میں تھے وہاں فرمایا تھا وَاِذَاالْبِحَارُ سُجِّرَتْ اور یہاں فرمایا ہے وَاِذَاالْبِحَارُ فُجِّرَتْ مَیں بتا چکا ہوں کہ سورۂ انفطار میں ایک مخصوص مضمون کی طرف اشارہ ہے جو عیسائیت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اس لئے یہ سب علامات عیسائیوں پر چسپاں ہوں گی.اِذَاالْبِحَارُ فُجِّرَتْمیں سمندر وںکے آپس میں ملائے جانے کی پیشگوئی مَیں سمجھتا ہوں اس آیت کے ایک معنے تو یہ ہیں کہ عیسائی اپنی ترقی کے زمانہ میں سمندروں کو پھاڑ کر آپس میں ملا دیں گے چنانچہ اِس کی نمایاں مثال نہر سویز اور نہر پانامہ پیش کرتی ہیں اور یہ دونوں عیسائیوں کی بنائی ہوئی نہریں ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں کہ دنیا میں بڑی بڑی شاندار نہریں پائی جاتی ہیں.ایرانیوں نے بھی نہریں بنائی ہیں.پٹھانوں نے بھی بنائی ہیں اور مغلوں نے بھی بنائی ہیں مگر اس فن میں گو یورپ نے بڑی ترقی کی ہے مگر وہ منفرد اور موجد نہیں مگر اس آیت میں جو علامت بتائی گئی ہے کہ سمندر پھاڑ کر آپس میں ملا دئے جائیں گے اس میںیورپ منفرد ہے اس سے پہلے دو سمندروں کو زمین
Page 375
پھاڑ کر نہیں ملایا گیا.سورۂ تکویر کی آیت وَاِذَاالْبِحَارُ سُجِّرَتْ کی تشریح میں دریائوں سے نہریں نکالے جانے کا مفہوم اس بناء پر بیان کیا گیا تھا کہ وہ سورۃ آخری زمانہ سے تعلق رکھنے والے عام حالات کی طرف راہنمائی کرتی تھی لیکن یہ سورۃ ایسی ہے جس کاعیسائیوں کے ساتھ خاص طور پر تعلق ہے اور اس سورۃ میں انہی علامات کا ذکر پایا جاتا ہے جو مخصوص طور پر عیسائی اقوام میں پائی جانے والی تھیںاور چونکہ سمندروں کو پھاڑ کر آپس میں ملا دینے کی اس سے پہلے اور کوئی مثال دنیا میں نہیں ملتی اس لئے پہلی آیت میں جہاں عام حالات کو مدِّنظر رکھتے ہوئے بحار سے دریا مراد لئے گئے تھے وہاں اس جگہ عیسائیوں کے مخصوص حالات کو مدِّنظر رکھتے ہوئے بحار سے سمندر مراد لئے جائیں گے اور معنے یہ ہوں گے کہ وہ سمندروں کو چیر کر ایک دوسرے سے ملا دیں گے.اِذَاالْبِحَارُ فُجِّرَتْ میں یہ اشارہ کہ کلیسیا گندہ ہو جائے گا دوسرےؔ معنے اس کے یہ بھی ہو سکتے ہیں اور ہیں کہ بحر اس جگہ وسیع علم رکھنے والے انسان کے معنوں میں استعمال ہوا ہے اس صورت میں وَاِذَاالْبِحَارُ سُجِّرَتْ کے یہ معنے ہوںگے کہ جس وقت مسیحی پادریوں کی طرف سے کثرت سے فسق وفجور منسوب کیا جائے گا گویا اِدھر عیسائیت دنیا پر غالب آجائے گی اور شرک کی تعلیم لوگوں میں پھیلا دے گی اور دوسری طرف کلیسیا بالکل گندی ہو جائے گی.گویا جسمانی لحا ظ سے تو اس کے یہ معنے ہوں گے کہ وہ سمندروں کو پھاڑیں گے اور روحانی لحاظ سے اس کے یہ معنے ہوں گے کہ کلیسیا بالکل خراب ہو جائے گی.اِذَاالْبِحَارُ فُجِّرَتْکے یہ معنے کہ دریاؤں کے دہانے کھولے جائیں گے تیسرے معنی اس کے یہ ہیں کہ اس زمانہ میں دریائوں کو وسیع کر دیا جائے گا اور ان کا راستہ کھلا کر دیا جائے گا چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانہ میںیورپ اور امریکہ کے بہت سے دریائوں کے دہانے اس طرح کھول دئے گئے ہیں کہ بڑے بڑے جہاز ان میں سے گزر جاتے ہیںپہلے سمندروں کے قریب جا کر دریا پھٹ جاتے تھے.اور پھیل کر چھوٹی چھوٹی نالیوں میں سمندر ملتے تھے مگر اس زمانہ میں بہت سے دریا فرانس ، جرمنی،آسٹریا، انگلینڈ اور امریکہ کے دہانوں کے پاس ایک گہرے نالے کی صورت میں بدل دئیے گئے ہیںجن کی وجہ سے وہاں جہاز بھی چلنے لگے ہیں اور بعض جگہ تو سو سو دو دو سو میل تک جہاز سمندر کے دہانہ سے دریا کے ذریعہ سے اندرون ملک میں چلے جاتے ہیں اور اس طرح اموال تجارت بہ سہولت اور تھوڑے خرچ پر مُلک سے باہر بھی جاتا ہے اور اندر بھی آ جاتا ہے.
Page 376
وَ اِذَا الْقُبُوْرُ بُعْثِرَتْۙ۰۰۵ اور جب قبریں اکھیڑ کر (اِدھر اُدھر) بکھیر دی جائیں گی.حَلّ لُغَات.بُعْثِرَتْ بُعْثِرَتْ بَعْثَرَ سے مجہول کا مؤنث کا صیغہ ہے اور بَعْثَرَالشَّیْئَ کے معنے ہوتے ہیں فَرَّقَہٗ وَبَدَّدَہٗ کسی چیز کو پراگندہ کر دیا.اور بَعْثَرَ الْقَبْرَ کے معنے ہوتے ہیں اِسْتَخْرَجَہٗ فَکَشَفَہٗ وَاَثَارَ مَا فِیْہِ.اُس نے قبر کی مٹی کو نکالا اور جو اس کے اندر تھا اسے ننگا کر دیا اور پھر اسے باہر نکال کر پھیلا دیا (اقرب) پس وَاِذَاالْقُبُوْرُ بُعْثِرَتْ کے معنے ہوں گے جبکہ قبریں اُکھیڑ ی جاویں گی (۲)اور ان کے اندر سے جو کچھ نکلے گا اسے پھیلا دیا جائے گا.تفسیر.یہ چیز بھی ہم کو اس زمانہ میں عیسائیوں میں بڑی شدّت سے نظر آتی ہے.پہلے زمانوں میں قبرستانوں کی اس قدر عزّت کی جاتی تھی کہ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر سامنے قبرستان آجاتا تھا تو لوگ اپنے شہر کا رُخ بدل دیا کرتے تھے اور یہ برداشت نہیں کرتے تھے کہ قبرستانوں کے احترام میں کوئی فرق آئے مگر اس قوم میں قبرستا نوں کا ادب بالکل نہیں رہا دِلّی بناتے وقت اُنہوں نے سینکڑوں قبرستان اُکھیڑ دیئے اور اُن کی ذرا بھی پروا نہ کی.پُرانی تاریخ کو ہم پڑھتے ہیں تو حیرت آتی ہے کہ اُن کے دلوںمیں کس قدر مرنے والوں کا احترام تھا کہ قبرستان سامنے آنے پر وہ شہر کا رُخ بدل دیتے.مگر یہ لوگ جب کسی جگہ شہر بسانے کا ارادہ کریں اور وہاں قبرستا ن ان کو دکھائی دے تو یہ بڑی جرأت سے اس کو اُکھیڑ کر پھینک دیتے ہیں اور جس رنگ میں چاہتے ہیں عمارت بنا لیتے ہیں پس اس کے ایک معنے یہ ہیں کہ کثرت آبادی کی وجہ سے قبرستان اُکھیڑ دئیے جائیں گے.بعثرۃ قبور سے مراد پھر بَعْثرۃ قبور سے مراد پُرانے مقبروں کا کھولنا بھی ہے جیسے مصر میں ہو رہا ہے کہ پُرانی قبریں کھود کھود کر ممّی بنائی ہوئی لاشیں نکالتے رہتے ہیں لغت نے اس لفظ کے کیا ہی اچھے معنے بتائے ہیں اِسْتَخْرَجَہٗ فَکَشَفَہٗ وَاٰثَارَ مَا فِیْہِ کہ قبر کی مٹی کو نکالا اور اسے ننگا کر دیا اور جو کچھ اس میں سے ملااس کو پھیلا دیا.عیسائی لوگ بھی قبریں کھودتے ہیں.ممیوں کو نکالتے ہیں اور ان میں سے کوئی فرانس کے میوزم میں بھیج دیتے ہیں کوئی انگلستان کے میوزیم میں بھیج دیتے ہیں کوئی امریکہ اور روس کے میوزیم میں بھیج دیتے ہیں گویا جس طرح جائیدادیں تقسیم کی جاتی ہیں اِسی طرح وہ لاشوں کو آپس میںتقسیم کرتے اور اپنے اپنے ممالک کے عجائب گھروں میں رکھتے ہیںپس یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پُرانے لوگوں کی لاشوں کو ان کی قبروں میں سے نکال نکال کر ننگا کر دیا ہے اور پھر
Page 377
مختلف ممالک میں پھیلا دیا ہے.میں سمجھتا ہوں جب مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو ان کا فرض ہے کہ وہ ان لاشوں کو پھر قبروں میں دفن کر دیں کیونکہ یہ بڑی گندی بات ہے کہ لاشیں نکال نکال کر لوگوں کے سامنے رکھی جائیں اور ان کی تحقیر و تذلیل کی جائے.فرعونِ مصر کی لاش کو بھی وہ اِسی طرح زمین میں دفن کر دیںاور اس پر ایک کتبہ لگا کر لکھ دیا جائے کہ یہاں فرعون مصر کی لاش دفن ہے.قبر کا لفظ چونکہ عام دفن شدہ چیزوں کے لئے بھی بولا جا سکتا ہے اس لئے اس کے ایک یہ معنی بھی ہیں کہ اس زمانہ میں پُرانے شہر زمین میں سے نکالے جائیں گے چنانچہ اب اُن کے دفینے نکال نکال کر مختلف عجائب گھروں میں تقسیم ہو رہے ہیں اسی طرح اس کے ایک یہ معنے بھی ہو سکتے ہیں کہ پُرانے کتب خانے باہر آجائیں گے اور پُرانی عمارات اور قبرستانوں کا پتہ لگ جائے گا.عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَ اَخَّرَتْؕ۰۰۶ وہ بڑی (خطا کار) جان (جس کا یہاں ذکر ہے) جان لے گی.کہ کیا (کچھ) اُس نے آگےبھیجا ہے.اور کیا (کچھ) پیچھے چھوڑا ہے.تفسیر.یہاں اللہ تعالیٰ نے عَلِمَتْ کُلُّ نَفْسٍ نہیں فرمایا بلکہ عَلِمَتْ نَفْسٌ فرمایا ہے.ایسا کیوں فرمایا؟ اس کے متعلّق بعض مفسّرین کہتے ہیں کہ دوسری جگہ کُلُّ نَفْسٍ آگیا ہے اس لئے اس جگہ کُلُّ کا لفظ چھوڑ دیا گیا ہے وہ دوسری جگہ یہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یَوْمَ تَجِدُ کُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَیْرٍمُّحْضَرًا (آل عمران :۳۱)یعنی اُس دن سے ڈرو جس دن ہر شخص جو کچھ نیکی اس نے کی ہو گی اسے اپنے سامنے موجود پائے گا.اور جو بدی اس نے کی ہو گی اسے بھی پس مفسّرین کہتے ہیں کہ چونکہ اس جگہ کُلُّ نَفْسٍ کا ذکر آ گیا ہے اس لئے اس آیت میں صرف نَفْسٌ کہا گیا ہے کُلُّ نَفْسٍ نہیں کہا گیا میں تو یہ نہیں کہتاکہ قرآن کریم میں ایسا طریق تسلیم نہیں کیا جا سکتا اگر ایک جگہ صرف اشارہ ہو اور دوسری جگہ تفصیلًا ذکر ہو تو ایسا درست ہو سکتا ہے لیکن پھر بھی میںاُن کے استدلال کو درست تسلیم نہیں کر سکتا.عَلِمَتْ نَفْسٌ میں نکرہ کا استعمال برائے حقارت میرے نزدیک یہاں تنوین تحقیر کی ہے یعنی یہ نَفْس جس کا پہلے ذکر کیا جا چکا ہے یعنی نفس عیسائیت.یہ ذلیل جان (جو اپنا بُرا بھلا بھی نہیں سمجھتی یا یہ بھی نہیں سمجھتی کہ کس کام کو کرنا چاہیے تھا اور کس کام کو نہیں کرنا چاہیے تھا) جان لے گی اُس کو جو اس نے آگے بھیجا تھا اور جو کچھ اُس نے
Page 378
پیچھے کیا تھا چونکہ قبور کا اُکھیڑنا بڑا گندہ کام تھااور دوسری طرف انہوں نے اتنا بڑ ا شرک کیا تھا جس سے آسمان پھٹ گیا اور یہ دونوں کام ایسے ہیں جس سے فطرت کو گھن آتی ہے اس لئے ان کی تحقیر کرتے ہوئے فرماتا ہے یہ حقیر جان جان لے گی مَاقَدَّمَتْ وَاَخَّرَتْ جو کام اسے آگے کرنا چاہیے تھا اُسے اُس نے پیچھے کر دیا اور جو کام پیچھے کرنا چاہیے تھا اُسے اُس نے پہلے کر دیا.یہ الفاظ بھی اس کی حقارت کے لئے استعمال کئے گئے ہیں چنانچہ اِذَا السَّمَآءُ انْفَطَرَتْ میں بھی اسی طرف اشارہ کیا گیا تھا کہ خدا تعالیٰ کی ذات جسے مقامِ عالی دینا چاہیے تھا اُسے تو ان لوگوں نے نیچا کر دیا اور مسیح ؑ جو خدا تعالیٰ کے بندوں میں سے ایک بندہ تھا اُسے خدا کے تخت پر بٹھا دیا چنانچہ عیسائی حضرت مسیح ؑ سے ہی دُعائیں مانگتے ہیں خدا سے نہیں مانگتے گویا خدا تعالیٰ اُن کے نزدیک نعوذباللہ پنشن پر چلا گیا ہے اب خدائی کا کام صرف مسیح کے ہاتھ میںہے پس قَدَّمَتْ وَاَخَّرَتْ کا ایک نمونہ انہوں نے یہ دکھایا ہے کہ خدا کو ایک بندے کا درجہ دے دیا اور بندے کو خدا کا درجہ دے دیا اور دوسرا نمونہ یہ کہ گزشتہ وفات یافتہ لوگوں کی لاشوں کو نکال کر ایک تماشہ کے طور پر عجائب گھروں میں رکھتے ہیں اور چونکہ قَدَّمَتْ وَاَخَّرَتْ میں آگے پیچھے کا مفہوم ہوتا ہے اِس لئے اس کے یہ معنے بھی ہیں کہ وہ جان لیں گے کہ انہوں نے کس کام کو کیا اور کس کو نہ کیا.محاورہ میں بھی کہا جاتا ہے کہ تم نے کس کام کو اختیار کر لیا اور کس کو نہ کیا کس کو ترجیح دے دی اور کس کو نہ دی پس مطلب یہ ہوا کہ اِس ذلیل جان کو علم ہو جائے گا کہ کون سا کام کرنے والا تھا اور کون سا کام کرنے والا نہیں تھا یعنی وہ کام جو کرنے والے تھے وہ تو انہوں نے نہ کئے اور جو کام نہ کرنے والے تھے وہ انہوں نے کر لئے.ایک معنے اس آیت کے یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ جب اُوپر کے واقعات ظاہر ہوں گے شرک پھیل جائے گا اور بادشاہوں اور سرداروں کی طاقت توڑ کر رکھ دی جائے گی اور سمندر ملا دئے جائیں گے اور قبریں کھود کر بکھیر دی جائیں گی تو اس وقت اللہ تعالیٰ ایسے سامان پیدا کر دے گا کہ اس جان ناتوان کو جو اس طرح خدائی اپنے ہاتھ میں لینی چاہے گی معلوم ہو جائے گاکہ کیا کرنا چاہیے تھا اور کیا نہیں یعنے شرک کی بُرائی اور دنیا کے انہماک کی غلطی ان پر کھل جائے گی اور یہ پھر ایک دفعہ توحید کی طرف لوٹیں گے اور اپنی غلطیوں پر نادم ہوں گے.يٰۤاَيُّهَا الْاِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِۙ۰۰۷ اے انسان تجھے کس نے تیرے محسن رب کے بارے میں مغرور بنا دیا ہے.حل لغات.اَلْکَرِیْمُ اَلْکَرِیْمُ کے معنے ہیں ذُوالْکَرَمِ.احسان والا.(اقرب)
Page 379
تفسیر.يٰۤاَيُّهَا الْاِنْسَانُ میں الانسان سے مراد یہاں بھی اَلْاِنْسَان سے مراد ہر انسان نہیں بلکہ وہی عَلِمَتْ نَفْسٌ والا انسان مراد ہے کہ نفس دنی رکھنے والے انسان مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ آخر یہ تو بتا تجھے تیرے رب کریم پر جرأت کس نے دلائی.مَا غَرَّکَ کے معنے مَا غَرَّکَ بِفُلَانٍ عربی زبان کا ایک محاورہ ہے جس کے معنے ہوتے ہیں کَیْفَ اِجْتَرَأْتَ عَلَیْہِ (اقرب) تُو نے کس طرح اس کے خلاف جرأت سے کام لیا پس مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ کے معنے ہوں گے کَیْفَ اِجْتَرَ أْتَ عَلٰی مَعْصِیَۃِ اللّٰہِ وَاَمِنْتَ مِنْ عِقَابِہٖ وَلَمْ تَکُنْ ھٰذِہٖ الْجُرْأَۃُ جَائِزَۃً لَّکَ کہ تُو نے کس طرح اُس کی معصیت پر جُرأت کی اور اُس کے عذاب سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھ لیا حالانکہ یہ جرأت تیرے لئے مناسب نہیں تھی.رب کے ساتھ کریم کالفظ لانے کی وجہ کَرِیْم کا لفظ یہاں اُن کی اس جرأت کی عدم مناسبت کے اظہار کے لئے لایا گیا ہے.ایک فعل ایسا ہوتا ہے جو دوسرے کی شان کے لحاظ سے مناسب ہوتا ہے مگر بِرَبِّکَ کہہ کر بتایا کہ تجھے اپنے رب پر کس طرح جرأت ہوئی اور کَرِیْم کہہ کر بتایا کہ تمہارا یہ فعل تو کسی صورت میں بھی مناسب نہیں تھاکیونکہ وہ نہ صرف تمہارا رب تھا بلکہ رب کریم تھا اپنے رب کو کریم دیکھ کر توتمہارے اندر شرم اور حیا کا مادہ پیدا ہونا چاہیے تھا نہ یہ کہ اُلٹا اس کے احسانات سے نافرمان بن جاتے اور محسن کی ہتک کا موجب ہو جاتے.جائز موقع پر اگر کوئی جُرأت سے کام لیتا ہےتو اُس میں شرافت کا مادہ سمجھا جاتا ہے اور نا جائز موقع پر اگر کوئی جرأت دکھاتا ہےتو وہ تہّور سے کام لینے والا سمجھا جاتا ہے لیکن فرماتا ہے تمہارا یہ فعل تو تہّور بھی نہیں.اس میں تو کمینگی اور رذالت پائی جاتی ہے کہ تم نے محسن کشی کی اپنے رب کو کریم دیکھ کر بجائے اس کے کہ اس کی اطاعت کرتے تم نے اس کی نافرمانی کرنی شروع کر دی اور ایسے عقائد اختیار کر لیے جو خدا تعالیٰ کی شان کے بالکل خلاف ہیں.آیتمَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ میں لفظ کریم پر پہلے مفسرین کی ضمنی بحثیں یہاں بھی مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ کے ماتحت ضمنی بحث کے طور پر مفسّرین نے عجیب عجیب باتیں بیان کی ہیں.بعض صوفیاء نے لکھا ہے کہمَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ میں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جب خدا تعالیٰ تمہارےجرموں کے متعلق تم سے سوال کرے تو تم اُسے کیا جواب دو.اور وہ جواب یہ ہے کہ ہمارا رب چونکہ کریم ہے اس لئے ہمیں غرور پید اہوا اور ہم نے یہ گناہ کئے.چنانچہ بقول ان کے حضرت فضیلؓ سے کسی نے پوچھا کہ آپ خدا تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے تو انہوں نے کہا میں تو خدا تعالیٰ سے یہ کہوں گا کہ تیرے عفو اور احسانات کے پردوں نے مجھے مغرور کر دیا(الکشاف زیر آیت ھذا).مگر اس طرف اُن کا ذہن اس وجہ سے گیا ہے کہ انہوں نے ساری سورۃ کے معنے نہیں سمجھے.صرف ایک ٹکڑہ لے لیا اور
Page 380
اُس سے انہوں نے استدلال کر لیا.اگر وہ دیکھتے کہ اس سورۃ میں صرف دشمنانِ اسلام کا ذکر ہو رہا ہے تو وہ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ کو کبھی مسلمانوں پر چسپاں نہ کرتے.ہمارے ملک میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ ع کرم ہائے تو مارا کرد گستاخ اگر اس فقرہ کو استعارۃً کسی وقت استعمال کر لیا جائے اور ’’کردگستاخ‘‘ سے مراد گستاخی نہ لی جائے بلکہ بے تکلّفی مراد لی جائے اور یہ سمجھا جائے کہ جس سے انسان بے تکلّف ہوتا ہے اس سے بے تکلّفی میں بعض دفعہ ایسی بات بھی کہہ لیتا ہے جو دوسری حالت میں نہیں کہی جا سکتی تو اور بات ہے لیکن اگر گستاخی سے حقیقی گستاخی مراد ہو تو یہ قطعًا غلط ہے.کرم انسان کو گستاخ نہیں بنایا کرتا بلکہ اس کے اندر محبت اور اطاعت کا مادہ زیادہ پیدا کر دیا کرتا ہے.یُوں تو اس فقرہ کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بھی استعمال کیا ہے (براہین احمدیہ روحانی خزائن جلد ۱ صفحہ ۶۶۲) اور ہم بھی بعض دفعہ یہ فقرہ استعمال کر لیتے ہیں مگر واقعہ یہی ہے کہ جہاں کرم ہو وہاں کرم انسان کو حقیقی طور پر گستاخ نہیں بنا سکتا.اس آیت کے ضمن میں مفسّرین حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ بھی بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک دفعہ اپنے ایک نوکر کو آواز دی مگر وہ نہ بولا.آپ نے بار بار آواز دی مگر پھر بھی اس نے کو ئی جواب نہ دیا تھوڑی دیر کے بعد وہ لڑکا اتفاقًا آپ کو سامنے نظر آگیا تو آپ نے اس سے پُوچھا مَالَکَ لَمْ تُـجِبْنِیْ کہ تجھے کیا ہو گیا کہ مَیں نے تجھے اتنی بار بلایا مگر تُو پھر بھی نہیں بولا.قَالَ لِثِقَتِیْ بِحِلْمِکَ وَاَمْنٍ مِنْ عَقُوْبَتِکَ فَاسْتَحْسَنَ جَوَابَہٗ وَاُعْتَقَہٗ (الکشاف زیر آیت ھذا) اس نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ مجھے آپ کی نرمی کا یقین تھا اور آپ کی سزا سے میں اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہوں اِس لئے میں نے آ پ کی بات کا جواب نہ دیا حضرت علی ؓ کو اس لڑکے کا یہ جواب پسند آیا تو آپ نے اسے آزاد کر دیا.وہ کہتے ہیں یہ واقعہ بھی اس بات کی تائید کرتا ہے کہمَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ میں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ عنایات اور عفو کا سلوک بھی انسان کو گناہوں پر دلیر کردیتا ہے اگر یہ محض ذوقی بات ہے واقعہ بڑا عمدہ ہے مگر اس کا مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ والی آیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس لڑکے نے جب دیکھا کہ حضرت علیؓ اب مجھ پر ناراض ہوں گے تو اُس نے یہ لطیفہ بنا لیا جو حضرت علیؓ کو پسند آگیا.اس سے یہ کس طرح معلوم ہو گیا کہ زیر بحث آیت میں بھی اسی مضمون کی طرف اشارہ ہے.یہ محض ذوقی باتیں ہیں سعدی نے لکھا ہے کہ ع پادشاہاں گاہے بسلامے برنجندد گاہے بہ دشنام خلعت دہند (گلستان سعدی صفحہ ۴۹.۵۰ )
Page 381
بادشاہ کبھی تعریف سے ناراض ہو جاتے ہیں اور کبھی گالی پر خلعت دے دیتے ہیں.مگر ایسی باتوں سے کوئی اصول مستنبط نہیں ہو سکتا یہی کہنا پڑتا ہے کہ مختلف انسان مختلف رنگ کا مذاق رکھتے ہیں اور پھر ان کی حالتیں بھی مختلف اوقات میں بدلتی رہتی ہیں اس لئے کبھی کسی بات سے وہ خوش ہو جاتے ہیں اور کبھی کسی بات سے بگڑ جاتے ہیں جہانگیر کا واقعہ ہی بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے نور جہان کے ہاتھ میں دو کبوتر پکڑا دیئے اتفاقًا ایک کبوتر نور جہاں کے ہاتھ سے چھوٹ گیا.تھوڑی دیر کے بعد جہانگیر واپس آیا تو اس نے پوچھا کہ دوسرا کبوتر کہاں گیا.اس نے کہا اُڑ گیا ہے.جہانگیر نے غصّہ سے پوچھاکس طرح اُڑ گیا.اُس نے دوسرا کبوتر بھی اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیا اور کہا کہ اس طرح.جہانگیر کو اس کی یہ ادا ایسی پسند آئی کہ وہ اسی وقت سےاس پر عاشق ہو گیا اور چونکہ باپ کی مخالفت کی وجہ سے اس سے شادی نہ کر سکا باپ کے مرنے کے بعد اس کے بیوہ ہونے پر اس سے شادی کر لی(تاریخ ہندوستان مولوی ذکاء اللہ جلد ششم صفحہ ۷۳زیر عنوان نور جہان و جہانگیر کا نکاح).تو بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ کسی کی بُری بات بھی اچھی لگتی ہے لیکن یہ آیت کی تفسیر نہیں کہلا سکتی.ممکن ہے حضرت علیؓ نے ایک بچہ کے مُنہ سے جب یہ بات سُنی ہو تو خواہ یہ گستاخی کا ہی رنگ رکھتی ہو مگر آپ نے یہ دیکھ کر کہ اس نے اپنے بچائو کے لئے کیسا عجیب طریق اختیار کیا ہے آپ نے اسے آزاد کر دیا مگر بہرحال یہ ایک انفرادی واقعہ ہے.قرآن کریم کی تفسیر ایسے واقعات سے نہیں کی جا سکتی.ایک سبق آموز واقعہ اسی سلسلہ میں امام قشیری نے اپنی کتاب شرح الاسماء میں ایک عجیب واقعہ لکھا ہے جس سے نصیحت کا پہلو بھی نکلتا ہے مجھے یہ واقعہ بہت پسند آیا اور گو یہ واقعہ بھی میرے نزدیک ہر گز یہاں چسپاں نہیں ہوتا مگر یہ بتانے کے لئے کہ انسانی فطرت سزا سے بچنے کے لئے کیا کیا حیلے نکال لیتی ہے اس کو بیان کرتا ہوں وہ لکھتے ہیں کسی بزرگ نے بیان کیا ہے کہ مَیں بصرہ کے بازار میں سے گزر رہا تھا کہ اچانک مَیں نے ایک جنازہ دیکھا جس کے ساتھ صرف چار آدمی تھے مَیں نے کہا بصرہ میں ایک مسلمان مر جائے اور اُس کے جنازہ کے ساتھ صرف چار آدمی اور وہ بھی چارپائی اُٹھانے والے ہوں یہ تو بہت بُری بات ہے.مَیں اس کے جنازہ کے ساتھ ضرور جائوں گا.چنانچہ مَیں بھی ساتھ ہو لیا جب وہ لوگ نعش کو دفن کر کے واپس آنے لگے تو مَیں نے اُن سے کہا یہ کیا بات ہے کہ بصرے جیسے بڑے شہر میں ایک مسلمان مرتا ہے اور اس کے جنازہ کے ساتھ صرف چار آدمی آتے ہیں وہ کہنے لگے ہم چاروں بھی جنازہ کی نیت سے نہیں آئے ہم تو مزدور ہیں یہ عورت جو سامنے کھڑی ہے ہمیں مزدوری پر لائی ہے پس ہم بھی مسلمان ہونے کی حیثیت سے نہیں آئے بلکہ مزدوروں کی حیثیت سے آئے ہیں.وہ کہتے ہیں اس جواب سے میری حیرت اور بھی بڑھ گئی کہ پہلے تو میں سمجھتا تھا بصرہ کے کم از کم چار مسلمان تو اس جنازہ کے ساتھ آئے ہیں مگر اب
Page 382
معلوم ہوا کہ ایک بھی نہیں آیا کیونکہ جو ساتھ آئے ہیں وہ صرف مزدور ہیں آخر اس کی وجہ کیا ہے یہ جواب دے کر وہ مزدور تو چلے گئے اور اُس عورت نے جو اُن کو لائی تھی آسمان کی طرف اپنے ہاتھ اٹھا کر دُعا مانگنی شروع کر دی.جب دُعا مانگ چکی تو اس نے قہقہ لگایا اور اپنے گھر کی طرف چل پڑی.وہ کہتے ہیں میں یہ نظارہ دیکھ کر مبہوت سا ہو گیا کہ یہ تماشہ کیا ہو رہا ہے چنانچہ مَیں نے اس عورت کا دامن پکڑ لیا اور کہا کہ مائی مَیں نے تجھے جانے نہیں دینا پہلے مجھے بتائو کے اصل حقیقت کیا ہے.اوّل تو اس جنازہ میں کوئی مسلمان شامل نہیں ہوا.پھر تُم نے دعا کی اور دُعا کے بعد ہنس پڑیں اِس کی وجہ بھی میری سمجھ میںکوئی نہیں آتی مجھے سچ سچ بتائو کہ یہ ماجرا کیا ہے اس نے کہا لو سنو یہ میرے لڑکے کا جنازہ تھا اور وہ سخت بدکار اور گنہ گار تھا قسم قسم کے گناہوں میں وہ مبتلا رہتا تھا اور باوجود سمجھانے کے اپنی حرکات سے باز نہیں آتا تھا چند دن گزرے کہ یہ بیمار ہو گیا.جب اس کی بیماری پر تین دن ہو گئے تو اس نے مجھے بلایا اور کہا امّاں مَیں اب بچتا نظر نہیں آتا.جب میں مر جائوں تو ہمسائوں کو خبر نہ دینا کیونکہ وہ میری موت سے خوش ہوں گے اور کہیں گے کہ اچھا ہوا وہ مر گیاہے اور پھر جنازہ میں بھی انہوں نے شامل نہیں ہونا اس لئے انہیں اطلاع دینے کی کوئی ضرورت نہیں.مزدور لے کر مجھے دفن کرا دینا صرف اتنی مہربانی کرنا کہ ایک انگوٹھی پر لَآ اِلَہَ اِلَّا اللّٰہُ لکھ کر میری انگلی میں ڈال دینا اور میری لاش کو نہلا دُھلا کر میرے چہرہ پر اپنا پَیر رکھ کر کہنا کہ خدا کے گنہ گاروں کی یہی سزا ہوتی ہے پھر جب مجھے دفن کر چکو تو ہاتھ اُٹھا کر میرے لئے دُعا کرنا اور کہنا اَللّٰھُمَّ اِنِّیْ رَضِیْتُ عَنْہُ فَارْضِ عَنْہُ اے اللہ میں اس سے راضی ہوں تو بھی اس سے راضی ہو جا.وہ کہنے لگی مَیں نے اس کی موت کے بعد جس طرح اُس نے کہا تھا اسی طرح کیا.نہلا دُھلا کر اس کے مُنہ پر مَیں نے اپنا پائوں رکھا اور کہا کہ یہی جزا اس شخص کی ہے جو خدا تعالیٰ کی نافرمانی کرے اور مَیں نے محلہ والوں کو بھی اطلاع نہ دی اور پھر چار مزدور اُجرت پر لے لئے اور انہیں ساتھ لےکر اپنے بیٹے کو دفن کر دیا جب میں دفن کر چکی تو مَیں نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ یا اللہ مَیں نے اس کے سب گناہ بخش دئے ہیں تو تو بہت زیادہ رحیم و کریم ہے تُو بھی اپنے فضل سے اس کو بخش دے.جب میں یہ دُعا کر چکی تو یکدم مجھ پرکشفی حالت طاری ہوئی اور مَیں نے اپنے لڑکے کی یہ آواز سنی جو نہایت صاف طور پر مجھے سنائی دی کہ اِنْصَرِ فِیْ یَا اُمِّی فَقَدْ قَدِمْتُ عَلٰی رَبٍّ کَرِیْمٍ فَرَضِیَ عَنِّیْ اس پر خوش میں میری ہنسی زور سے نکل گئی.(روح البیان زیر آیت ھذا) یہ واقعہ اللہ بہتر جانتا ہے صحیح ہے یا غلط.امام قشیری بڑے پایہ کے آدمی ہیں اس لئے ممکن ہے یہ واقعہ انہوں نے تحقیق سے ہی لکھا ہو رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم نے بھی اس رنگ میں فرمایا ہے کہ بعض دفعہ ایک آدمی دوزخیوں کے کام کرتا چلا جاتا ہے مگر اُس کے اندر کوئی نیکی مخفی ہوتی ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب بُرے اعمال کرتے کرتے
Page 383
وہ جہنّم میں گرنے کے قریب پہنچ جاتا ہے تو یکدم اللہ تعالیٰ کے فضل کا ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہے اور وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے.اور ایک دوسرا آدمی جنّت کے مستحق بنانے والے اعمال کرتا چلا جا تا ہے مگر اُس کے دل میں کوئی بدی مخفی ہوتی ہے جب نیک اعمال کرتے کرتے وہ ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ قریب ہوتا ہے وہ جنّت میں داخل ہو جائے تو یکدم اُس کی چھپی ہوئی بدی ظاہر ہو جاتی ہے اور وہ جہنّم میں جا پڑتا ہے(صحیح بخاری کتاب القدر باب ما جاء فی القدر).پس یہ روایت خواہ بناوٹی ہے یا حقیقی لیکن بہرحال سبق آموز ہے اور چونکہ مجھے یہ روایت بہت پسند آئی ہےاس لئے گو میرے نزدیک اس آیت سے اس کا کوئی تعلق نہیں مگر مَیں نے اسے بیان کر دیا ہے.اس کا اپنی ماں کو یہ کہنا کہ مرنے کے بعد میرے چہرہ پر اپنے پیر رکھ کر کہنا کہ یہ سزا اُس شخص کی ہے جو خدا تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے بتاتا ہے کہ اُس کے دل میں نیکی تھی اس نے سمجھا کہ مَیں بدی کے ایسے مقام پر پہنچا ہوا ہوںکہ اب میری زبان سے یہ بھی نہیں نکل سکتا کہ خدایا مَیں توبہ کرتا ہوں لیکن میرے نزدیک جب اس نے اپنی ماں سے کہہ دیا کہ میرے چہرہ پر اپنے پَیر رکھ کر یہ الفاظ کہنا تو عملی طور پر اُس نے توبہ کر لی معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو اس کی یہی ادا پسند آگئی اور اُس نے اسے جنّت میں داخل کر دیا.پس یہ روایت خواہ بناوٹی ہو یا واقعہ صحیح ہو بڑی عمدہ روایت ہے اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا کرشمہ انسان کی آنکھوں کے سامنے لے آتی ہے.مَا غَرَّکَ بِرَبِّکَ الْکَرِیْمِ میں لفظ کریم کی تشریح صحابہ ؓ کے نزدیک تفاسیر کی ان ذوقی باتوں کے مقابلہ میں صحابہؓ نے وہی طریق اختیار کیا ہے جو اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے ایک سمجھدار انسان اختیار کر سکتا ہے اور اس آیت کا جو مفہوم ثابت ہوتا ہے صرف اُس کو انہوں نے بیان کیا ہے ذوقی باتوں کی طرف وہ نہیں گئے چنانچہ سفیان بیان کرتے ہیں اَنَّ عُمَرَ سَمِعَ رَجُلًا یَقْرَئُ یٰٓاَیُّھَا الْاِنْسَانُ مَاغَرَّکَ بِرَبِّکَ الْکَرِیْمِ فَقَالَ عُمَرُ اَلْجَھْلُ (ا بن ابی حاتم.حوالہ ابن کثیر زیر آیت ھذا) کہ حضرت عمرؓ نے ایک شخص کو یہ پڑھتے سُنا کہ يٰۤاَيُّهَا الْاِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ اے انسان تجھے کس نے رب کریم پر جرأت دلا دی.حضرت عمرؓ نے کہا جہالت نے.اور کس نے.اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے بھی روایت ہے چنانچہ ابن ابی حاتم کہتے ہیں قَالَ ابْنُ عُمَرَ غَرَّہُ وَاللّٰہِ جَھْلُہٗ (ابن کثیر زیر آیت ھذا) کہ حضرت ابن عمرؓ نے کہا کہ خدا کی قسم اسے جہالت نے مغرور کر دیا.ابن عباس اور الربیع ابن خیثم اور حسن بصری سے بھی یہی مروی ہے (ابن کثیر زیر آیت ھذا) اور قتادہ سے آیت مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِکے متعلق روایت ہے وہ کہتے ہیں مَاغَرّابْنَ اٰدَمَ غَیْرُ ھٰذَا الْعَدُوِّ الشَّیْطٰنُ.(ابن کثیر) کہ ابن آدم کو کسی نے جرأت نہیں دلائی سوائے اُس دشمن کے جس کا نام شیطان ہے صوفیاء نے جو معنے کئے ہیں وہ اس بنا پر کئے
Page 384
ہیںکہ وہ کہتے ہیںيٰۤاَيُّهَا الْاِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ میں انسان سے سوال کیا گیا ہے کہ تجھے کس چیز نے مغرور کیا تھا مگرآگے الْکَرِیْم کا لفظ استعمال فرما کر اللہ تعالیٰ نے خود ہی جواب سکھا دیا ہے کہ کہہ دینا کریم خدا کی بخشش اور عفو نے ہمیں یہ جرأت دلا دی تھی.لیکن مشاہدہ بتاتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی بخشش اور عفو کی وجہ سے انہیں گناہوں پر دلیری نہیں ہوئی بلکہ ان کی دلیری کی وجہ یہ تھی کہ وہ شیطان کے پیچھے چل پڑے اور خدا تعالیٰ کے نافرمان بن گئے یا یہ کہ اُن سے یہ گناہ ان کی جہالت کی وجہ سے سرزد ہوئے.اگر وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو سمجھتے اس کی اطاعت کی قدر وقیمت کو جانتے اور بصیرت سے کام لیتے تو ایسے افعال کے وہ مرتکب نہ ہوتے.اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مومن خدا تعالیٰ کو کریم سمجھتا ہے اور وہ اس کی بخشش اور عفو پر ہر لحظہ یقین رکھتا ہے مگر گناہوں کے ارتکاب کی اسے وجہ قرار دینا کسی صورت میں بھی درست نہیں ہو سکتا.اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں صاف طور پر فرماتا ہے کہ گناہوں کے ارتکاب کی بڑی وجہ انسان کی جہالت ہوتی ہے فرماتا ہے مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوْٓءًۢا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْۢ بَعْدِهٖ وَ اَصْلَحَ فَاَنَّهٗ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (الانعام:۵۵) یعنی جو کوئی تم میں سے نادانی سے کچھ برائی کا کام کرےگا.پھر اس کے بعد توبہ کر لے گا.اور نیک کام کرنے لگے گا تو اللہ اس کے گناہ بخش دے گا کیونکہ وہ بخشنے والا مہربان ہے.پس جو شخص بھی گناہ کرتا ہے درحقیقت جہالت سے کرتا ہے.دیدہ ودانستہ تو وہی گناہ کرے گا جو کافر ہو گا.اس لئے یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ انسان کو شیطان کی اتباع مغرور کر دیتی ہے یا اس کی جہالت اسے دھوکا دےدیتی ہےمگریہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس جرأت اور غرور کا موجب خدا تعالیٰ کا کرم اور بخشش ہوتی ہے سوائے اس کے کہ اسے ایک غیر طبعی نتیجہ قرار دیا جائے جو خود ایک نفس کی بیماری کہلائے گا.خدا تعالیٰ کے کرم کے نتیجہ میں انسان اپنے ایمان اور اپنے عرفان میں ترقی کیا کرتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ وہ گناہوں پر دلیر ہو جائے پس یہ بالکل غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کرم انسان کے لئے گناہوں پر جرأت کرنے کا موجب ہو جائے بے شک مومن خدا تعالیٰ کے کرم پر بڑا یقین رکھتا ہے اور وہ خدا تعالیٰ کی رحمت کا ہمیشہ امیدوار ہتا ہے.مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِکا مخاطب مومن نہیں بلکہ کا فر ہے لیکن سوال یہ ہے کہ یہاں اس بات کے بیان کرنے کا کون سا موقع تھا یہاں تو کفار کا ذکر ہو رہا ہے لیکن ہمیں بتایا یہ جا رہا ہے کہ ا للہ تعالیٰ کفّار سے کہے گا کہ جب میں تمہارے گناہوں کی تم سے پرسش کروں تو تم مجھے کہہ دینا.آپ جو کریم خدا تھے آپ کے کرم نے ہی ہمیں مغرور کر دیا تھا.کیا کوئی عقل تسلیم کرسکتی ہے کہ ایک طرف کفّار کے متعلق ناراضگی کا اظہار کیا جارہا ہو اور دوسری طرف یہ راز ونیاز کی باتیں بھی ہو رہی ہوں مومنوں کا ذکر ہوتا تب تو کسی حد تک یہ بات معقول بھی قرار دی جا سکتی تھی مگر
Page 385
یہاں تو کفار کا ذکر ہے خدا تعالیٰ اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں نےاتنا بڑا جرم کیا ہے جس سے آسمان پھٹ گیا ہے مگر بنایا یہ جا رہا ہے کہ خدا نے آگے انہیں خود ہی جواب سکھا دیا ہے کہ تمہارا جرم بے شک سخت ہے مگر مجھے یہ جوا ب دے دینا تو مَیں تمہیں معاف کر دُوں گاایسے خطرناک عذاب کے وقت تو اس قسم کی راز و نیاز کی باتوں کی طرف خیال بھی نہیں کیا جا سکتا مگر نہ معلوم صوفیاء کو کیا سوجھا کہ اس آیت سے انہوں نے یہ نکتہ نکال کر پیش کر دیاحالانکہ اس آیت میں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ربّ کریم کے سامنے تو تمہیںشرم کرنی چاہیے تھی مگر تم ایسے گستاخ اور بے ادب نکلے کہ تم نے اپنے رب کریم کی بھی پروا نہ کی.خود رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ کریم سے شرم کی جاتی ہے.حدیثوں میں آتا ہے ایک دفعہ رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں لیٹے ہوئے تھے اور آپؐ کی ٹانگوں کا کچھ حصہ ننگا تھاکہ حضرت ابو بکرؓ آئے اور بیٹھ گئے پھر حضرت عمرؓ آئے اور بیٹھ گئے مگر آپؐ نے کوئی پرواہ نہ کی.تھوڑی دیر گزری تھی کہ حضرت عثمانؓ نے دستک دے دی.آپ فوراً اٹھ بیٹھے اور اپنی ٹانگوں کو کپڑے سے ڈھانک لیا اور فرمایا عثمانؓ بہت شرمیلا ہے اُس کے سامنے ٹانگ کا کچھ حصہ ننگا رکھتے ہوئے شرم آتی ہے.چنانچہ حدیث کے یہ الفاظ ہیں اَنَّ عَائِشَۃَ قَالَتْ کَانَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ مُضْطَجِعًا فِیْ بَیْتِہٖ کَاشِفًا عَنْ فَـخِذَیْہٖ اَوْسَاقَیْہِ فَاسْتَاْذَنَ اَبُوْ بَکْرٍ فَاَذِنَ لَہٗ وَھُوَ عَلٰی تِلْکَ الْحَالِ فَتَحَدَّثَ ثُمَّ اِسْتَاْذَنَ عُمَرُ فَاَذِنَ لَہٗ وَھُوَ کَذٰلِکَ فَتَحَدَّثَ ثُمَّ اَسْتَاْذَنَ عُثْمَانُ فَجَلَسَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صلَّ اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّمَ وَسَوَّیٰ ثِیَابَہٗ فَلَمَّا خَرَجَ قَالَتْ عَائِشَۃُ دَخَلَ اَبُوْ بَکْرٍ فَلَمْ تَھْتَشَّ لَہٗ وَلَمْ تُبَالِہٖ ثُمَّ دَخَلَ عُمَرُ فَلَمْ تَھْتَشَّ لَہٗ وَلَمْ تُبَالِہٖ ثُمَّ دَخَلَ عُثْمَانُ فَجَلَسْتَ وَسَوَّیْتَ ثِیَابَکَ فَقَالَ اَلَا اَسْتَحْیٖ مِنْ رَجُلٍ تَسْتَحْییٖ مِنْہُ الْمَلَائِکَۃُ (مسلم کتاب فضائل الصحابۃ باب من فضائل عثمان بن عفان) یعنی حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ ایک دفعہ رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم گھر میںلیٹے ہوئے تھے.اور اپنی پنڈلیوں سے کپڑا ہٹایا ہوا تھا اسی حالت میں ابو بکرؓ نے اندر آنے کی اجازت چاہی تو آپ ؐاسی طرح لیٹے رہے.اور آپؐ نے اجازت دے دی اور ان سے گفتگو فرماتے رہے.پھر عمرؓ آئے.اور انہوں نے اجازت طلب کی اور آپؐ نے اجازت دے دی اور اسی طرح لیٹے رہے.پھر تھوڑی دیر بعد عثمانؓ آئے تو نبی کریم صلے اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے اور کپڑے کو درست کر لیااور ان کو اندر آنے کی اجازت دے دی جب سب چلے گئے تو حضرت عائشہ نے نبی کریم صلے اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ ابو بکر آئے اور عمر آئے تو آپ ؐنے ان کی آمد پر خاص پروا نہ کی اور اسی طرح لیٹے رہے جیسے لیٹے تھے.لیکن عثمان کی آمد پر آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور کپڑے ٹھیک کر لئے.آ پؐ نے جواب دیا
Page 386
اے عائشہ کیا مَیں اس سے شرم نہ کروں جس سے فرشتے بھی شرم کرتے ہیں.تو دیکھو رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم نے عثمانؓ کی شرم کا لحاظ کیا کہ وہ لوگوں سے شرماتے تھے آپ اُن سے شرمائے.پھر ہم اس آیت سے یہ کس طرح مراد لے سکتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے کریم ہونے نے لوگوں کو گناہوں پر جرأت دلائی تھی.میرے نزدیک رب کریم کے الفاظ سے اسی طرف اشارہ ہے کہ انسان کو اپنے کریم خدا کی بات تو ما ننی چاہیے تھی نہ یہ کہ اُلٹا اس کی نافرمانی کرنے لگ جاتا.آیت مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِمیں کریم کہہ کر عیسائیت کے عقائد پر چوٹ میرے نزدیک مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِمیں عیسائیت کی طرف نہایت لطیف پیرایہ میں اشارہ کیا گیا ہے کیونکہ عیسائیت خدا تعالیٰ کے رحم پر بڑا زور دیتی ہے اور اُس کی بنیاد ہی اِس مسئلہ پر ہے کہ خدا محبت ہے.خدامہربان ہے(یوحنا کا پہلا خط باب ۴ آیت۸ ،لوقا باب ۶ آیت ۳۵.۳۶).گو تفصیلات میں وہ خدا تعالیٰ کو نعوذ باللہ بڑا ظالم بتاتے ہیںاور کہتے ہیں کہ وہ لوگوں کے گناہ معاف ہی نہیں کر سکتا.مگر بہرحال وہ خدا تعالیٰ کی رحمت پر زور دیتے ہیں اور پھرساتھ ہی یہ بھی کہتے جاتے ہیں کہ وہ لوگوں کے گناہ معاف نہیں کر سکتا.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ عجیب بات ہے کہ ایک طرف تو تم اللہ تعالیٰ کو کریم کہتے ہیں اور دوسری طرف ایسی صفات اُس کی طرف منسوب کرتے ہو جو اُس کے کریم ہونے کے خلاف ہیں اور تم اس کا ایک بیٹا تسلیم کرتے ہو اور کہتے ہوکہ اُس نے لوگوں کے گناہ معاف کرنے کی جب کوئی اور صورت نہ دیکھی تو اپنے بیٹے کو لوگوں کے گناہوں کے بدلہ میں قربان کر دیا(یوحنا کا پہلا خط باب ۴ آیت ۸ تا ۱۰).پس اس جگہ مومنوں کا ذکر نہیں بلکہ ایسے دشمن کا ذکر ہے جو ایک طرف خدا تعالیٰ کو رب کریم کہتا ہے اور دوسری طرف یہ بھی کہتا ہے کہ وہ گناہ معاف نہیں کر سکتا مجھے اِس وقت اچھی طرح یاد نہیں لیکن جہاںتک میرا خیال ہے عیسائی کتابوںمیں خدا تعالیٰ کے متعلق رحیم و کریم کا اکٹھا ذکر ہوتا ہے اور اگر نہ بھی ہو تب بھی کرم میں رحم شامل ہے بہرحال رب کریم کے الفاظ لا کر اس قوم کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو خدا تعالیٰ کو ایک طرف ربِّ کریم قرار دیتی ہے اور پھر دوسری طرف اُس پر اتّہام بھی لگاتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ گنہ معاف نہیں کر سکتا.فرماتا ہے اے انسان تجھے کس نے یہ جرأت دلائی کہ ایک طرف تو اسے رب کریم کہتا ہے اور دوسری طرف یہ بھی کہتا ہے کہ خدا گناہ معاف نہیں کر سکتا تھا اس وجہ سے اُس نے اپنے بیٹے کو صلیب پر قربان کر دیا.
Page 387
الَّذِيْ خَلَقَكَ فَسَوّٰىكَ فَعَدَلَكَۙ۰۰۸فِيْۤ اَيِّ صُوْرَةٍ (اس رب کے بارے میں) جس نے تجھے پیدا کیا پھر تجھے (یعنے تیری اندرونی قوتوں کو) درست کیا.پھر مَّاشَآءَ رَكَّبَكَؕ۰۰۹ (دوسری مخلوقات کے مقابلہ میں ) تجھے مناسب قوتیں بخشیں (پھر) جو صورت اس نے پسند کی اس میں تجھے ڈھالا.حل لغات.سَوَّیٰ سَوَّیٰ کے معنے ہوتے ہیں سب عیبوں اور نقصوں کو دُور کیا (اقرب) عَدَلَ کے ایک معنے نقص دور کرنے کے بھی ہوتے ہیں جیسے کہتے ہیں عَدَلَ السَّھْمَ: اَقَامَہٗ تیر کو بالکل سیدھا کیا اور اس کے نقص کو دُور کر دیا اور عَدَلُوْہُ کے معنے ہوتے ہیں قَوَّمُوْہُ اس کے نقص کو دُور کر دیا اِسی طرح عَدَلَ کے معنے موازنہ کرنے کے بھی ہوتے ہیں چنانچہ عَدَلَ فُلَانًا کے معنے ہوتے ہیں وَازَنَہٗ اس کا موازنہ کیا (اقرب) فِیْ اَیِّ سُوْرَۃٍ مَّا شَآئَ کی لوگ کئی ترکیبیں کرتے ہیں آسان تر صورت یہ ہے کہ مَا کو زائدہ قرار دے دیا جائے اور معنے یہ لئے جائیں کہ رَکَّبَکَ فِیْ اَیِّ سُوْرَۃٍ شَاءَ یعنی اُس نے اپنی مرضی کے مطابق تجھ کو صورۃ بخشی جسمانی بھی اور روحانی بھی.گویا شَائَ سے مراد وہ صورت ہو گی جو اُس نے خود پسند کی اور جسے اُس کی مشیّت نے ترجیح دی یعنے ایسا نہیں ہوا کہ اتفاقی طور پر انسان کو اِس صورت میں پیدا کر دیا گیا ہے بلکہ یہ وہ صورت ہے جسے خدا نے انسان کے لئے پسند کیا.تفسیر.اس آیت میں چار باتیں بیان کی گئی ہیں.اوّلؔ خدا تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا.دومؔ اس کا تسویہ کیایعنی ہر ذاتی نقص اور عیب کو دُور کیا.سومؔ پھر اس کی تعدیْل کی یعنی دوسری اشیاء کی نسبت سے اس کی اصلاح کی.چہارمؔ پھر اسے ایسی صورت دی جو خدا تعالیٰ کی چنندہ صورت تھی اس چنندہ صورت کے مطابق اس نے انسان کی تخلیق کی.یعنی اعلیٰ درجہ کے کمالات اس میں رکھے.یہ چار باتیں مسیحیوں کی گستاخی کو اور زیادہ بھیانک بنانے کے لئے ہیں.مسیحیت میں دو خطرناک عیب مسیحی تاریخ دو خطرناک عیبوں پر مشتمل ہے (۱) اللہ تعالیٰ کی گستاخی پر جس کی تفصیل یہ ہے (الف) اللہ تعالیٰ کا شرک (ب)اللہ تعالیٰ پر عیب لگانا کہ وہ معاف نہیں کرسکتا (ج)اللہ تعالیٰ پر الزام کہ آدم کا گنہ اس نے اولاد میں رکھ دیا (د)اللہ تعالیٰ پر الزام کہ وہ بے گناہ کو دوسروں کی خاطر سزا دیتا ہے اور اس
Page 388
طرح ظالم ہے (۲)بنی نوع انسان کے متعلق (الف)غرور اور کبر اپنے آپ کو ہر بات میں دوسری اقوام پر فضیلت دینا.(ب)دوسروں کی نیکیوں کو چھپانا اور ان کے احسانات کا انکار کرنا (۳)بنی نوع انسان کی فطرت کو گندہ قرار دینا اور اس کے مقابل پر اپنے اندر خدائی طاقتوں کا دعویٰ.اس کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرماتا ہے اے اوپر ذکر کئے ہوئے انسان یعنی مسیحی بتا تو کہ آخر کس بات نے تجھے مغرور کیا ہے اور پھر مغرور بھی رب کریم کے مقابل پر.یعنی ایک طرف تو خدا تعالیٰ کو گِراتا ہے دوسری طرف اپنے آپ کو بڑھاتا ہے ایک طرف تو یہ تسلیم کرتا ہے کہ تیرا رب کریم ہے اور دوسری طرف تیری یہ حالت ہے کہ تو ایک بندے کو خدا کا بیٹا بنا رہا ہے جس کی بُنیاد اس دلیل پر ہے کہ خدا لوگوں کے گناہ معاف نہیں کر سکتا.اور چونکہ وہ معافی دینے کی طاقت نہیں رکھتا تھااس لئے معافی کی قائمقام کوئی اور چیز ہونی چاہیے تھی سو وہ قائم مقام خدا تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو بنا کر بھیج دیا.جس نے لوگوں کے گناہوں کی خاطر اپنے آپ کو قربان کر دیا.یہی کفّارے کے مسئلہ کی بنیاد ہے جس پر عیسائی مذہب کی بنیاد ہے اور جس کی بناء پر وہ لوگوں میں حضرت مسیح ؑ کے ابن اللہ ہونے کا پراپیگنڈہ کرتے ہیں حالانکہ اصل بات یہ ہے کہ تورات میں اور بھی کئی انبیاء کو بلکہ یہود کی قوم کو بھی خدا تعالیٰ کا بیٹا قرار دیا گیا تھا.چنانچہ خروج باب ۴ آیت ۲۱،۲۲ میں لکھا ہے ’’خدا وند نے موسیٰ سے کہا کہ جب تو مصر میں پُہنچے تو دیکھو وہ سب کرامات جو مَیں نے تیرے ہاتھ میں رکھی ہیں فرعون کے آگے دکھانا.لیکن میں اس کے دل کو سخت کروںگا اور وہ ان لوگوں کو جانے نہیں دے گا.اور تُو فرعو ن سے کہنا کہ خدا وند یُوںفرماتا ہے کہ اسرائیل میرا بیٹا بلکہ میرا پلوٹھا بیٹا ہے اور میں تجھے کہہ چکا ہوں کہ میرے بیٹے کو جانے دے.‘‘ مسیح کو ابن اللہ کہے جانے کا مطلب پھر سلیمان کے متعلق خدا تعالیٰ کہتا ہے ’’ وہ میرا بیٹا ہو گا اور مَیں اس کا باپ ہونگا اور میں اسرائیل پر اس کی سلطنت کا تخت ابد تک قائم رکھوں گا.‘‘ (تواریخ باب ۲۲ آیت ۱۰)پس یہ سوال ہوسکتا تھا کہ جب اور انبیاء بلکہ صلحاء بھی خدا تعالیٰ کے بیٹے کہلاتے تھے تو حضرت مسیح ؑ کو بھی اگر ابن اللہ کہہ دیا گیا تو اس میں کون سی زائد خصوصیّت پیدا ہو گئی.اس لئے مسیحیوں نے یہ بات بنا لی کہ مسیح ؑ کی امتیازی شان یہ ہے کہ اس کی قربانی کے ساتھ لوگو ں کے گناہوں کی معافی وابستہ تھی اور چونکہ یہ خصوصیّت کسی اور نبی کو حاصل نہیں ہوئی اس لئے گو اُن کو بھی ابن اللہ کہا گیا ہے مگر وہ اَور معنوں میں ہے اور مسیح کو ابن اللہ اور معنوں میں کہا گیا ہے اسی طرح آہستہ آہستہ انہوں نے مسیح ؑ کی الوہیت کا مشرکانہ عقیدہ لوگوں کے قلوب میں راسخ کر دیا(قاموس الکتاب صفحہ ۷۹۲ زیر لفظ کفارہ).مسیحیوں کے گھمنڈ کی وجہ دوسری چیز جو عیسائیوں کے گھمنڈ کا موجب ہوئی وہ اُن کی طاقت اور قوت اور اعلیٰ
Page 389
درجہ کی مادی ترقیات ہیں اور یہ ترقیات اُن کو اس وجہ سے حاصل ہوئیں کہ انہیں اسلامی علوم بیج کے طور پر مل گئے تھے جن پر وہ اور عمارت بنا کر ترقّی کر گئے.مسلمانوں کو یونانی علم ملا تھا جس پر مزید تحقیق کر کے وہ ترقی کر گئے اور عیسائیوں کو مسلمانوں کا علم مل گیا.اس کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ وہ مسلمانوں سے زیادہ ترقی کر جاتے.جب انہیں ترقی حاصل ہوئی تو ان کے دماغ میں غرور پیدا ہونا شروع ہو گیا کہ جو ایجادات ہم نے کی ہیں وہ اب تک اور کسی قوم نے نہیں کیں اس طرح انہیں اپنی ترقیات کے متعلق فخر پیدا ہو گیا حالانکہ یہ اشیاء تو اُنہیں اور بھی اللہ تعالیٰ کی طرف جُھکانے والی ہونی چاہیے تھیں.الَّذِيْ خَلَقَكَ کہہ کر عیسائیوں کو توحید کی طرف متوجہ کرنا الَّذِيْ خَلَقَكَ کہہ کر اللہ تعالیٰ عیسائیوں کو اس طرف توجہ دلاتا ہے کہ تمہیں اس خدا کا تو خیال کرنا چاہیے تھا جس نے تمہیں پیدا کیا.بائبل میں لکھا ہے ’’خدا نے ساتویں دن کو برکت دی اور اسے مقدّس ٹھہرایا.کیونکہ اس میں خدا ساری کائنات سے جسے اس نے پیدا کیا اور بنایا فارغ ہوا.یہ ہے آسمان اور زمین کی پیدائش جب وہ خلق ہوئے جس دن خدا وند خدا نے زمین اور آسمان کو بنایا‘‘ (پیدائش باب ۲ آیت ۳ تا ۵)پھر لکھا ہے’’اور کہو خدا وند ہمارا خدا ازل سے ابد تک مبارک ہے تیرا جلالی نام مبارک ہو جو سب حمد و تعریف سے بالا ہے تو ہی اکیلا خدا وند ہے تُو نے آسمان اور آسمانوں کے آسمان کو اور ان کے سارے لشکر کو اور زمین کو اور جو کچھ اس پر ہے اور سمندروں کو اور جو کچھ ان میں ہے بنایا اور تُو اُن سبھوں کا پروردگار ہے.‘‘ (نحمیاہ باب ۹ آیت۵،۶)گویا آیت مذکورہ میں یہ توجہ دلائی ہے کہ جب وہی تمہارا خالق ہے تو تُم اس کی بادشاہت کو دوسروں کی طرف کیوں منسوب کرتے ہو.پھر خَلَقَکَ کے بعد سَوّٰکَ کہہ کر اسی طرف توجہ دلاتا ہے کہ اس نے تم کو تمام معائب اور نقائص سے پاک بنایا ہے انسانی فطرت میں جس قدر کمزوریاں تھیں اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کاملہ سے اُن کا علاج بھی انسانی فطرت کے اندر ہی رکھ دیا ہے انسان پر بڑی بڑی مشکلات آتی ہیں مگر ساتھ ہی اُن مشکلات کو برداشت کرنے کا مادہ بھی ظاہر ہو جاتا ہے.بیماریوں کے جراثیم حملہ کر کے آتے ہیں تو اُن کا توڑ انسانی نفس میں پہلے ہی موجود ہوتا ہے اور کئی قسم کی بیماریاں ہیں جو اندر ہی اندر فنا ہو جاتی ہیں پھر کیا وجہ ہے کہ جسمانی طور پر اس نے تمہارے علاج کے سامان تمہارے خون میں پیدا کئے ہیں اور روحانی اور اخلاقی علاج بھی تمہارے نفس میں پیدا کئے ہیں لیکن تمہاری نجات کے لئے اس نے ایک غیر طبعی طریقہ ایجاد کیا کہ ایک بے گنہ پھانسی پر لٹکا دیا تا تم کو نجات دلائے گویا وہ خون کا پیاسا ہے جب تک خون نہ پی لے کسی کو چھوڑتا نہیں.العیاذ باللہ.اسی طرح فَعَدَلَکَ فرما کر اس طرف توجہ دلائی کہ اس نے تمہارے نفس کی ہی اصلاح نہیں کی بلکہ تمہارے
Page 390
وجود کو بیرونی دنیا کی نسبت سے بھی ایسا بنایا ہے کہ وہ اس پر حکومت کا اہل ہے گویا جہاں ذاتی کمال بخشا تھا وہاں نسبتی کمال بھی بخشا ہے پھر خدا تعالیٰ کے اس فعل کے بعد یہ خیال کرناکہ انسان نجات پانے کے لئے خدا تعالیٰ کے بیٹے کی قربانی کا محتاج ہے کہاں تک درست ہو سکتا ہے اور اسی طرح خدائی قانون کے ماتحت ترقی کرنے والی اقوام کو دوسروں پر فخر کرنا اور انہیں ذلیل سمجھنا اور ذلیل قرار دینا کس طرح زیب دیتا ہے.عَدَلَکَ اور سَوّٰکَ میں امتیازی فرق یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ فَسَوّٰکَ میں صرف معمولی تسْویَہ کی طرف اشارہ نہیں جو جسم کے ساتھ تعلق رکھتا ہو بلکہ فَسَوّٰی سے یہ بات بھی ظاہر ہوتی ہے کہ اس نے انسان کے اندر ایسے اعلیٰ درجہ کے کمالات پیدا کر دیئے ہیں جن سے اگر وہ کام لے تو خدا تعالیٰ سے بھی مل سکتا ہے.فَعَدَلَکَ سے اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جس کام کے لئے اس نے انسان کو پیدا کیا تھا یعنے زمین پر خدا تعالیٰ کا نائب بننے کے لئے اس کے متعلق اس نے موازنہ کیا کہ وہ طاقتیں انسان کے اندر موجود ہیں یا نہیں یعنے وہ دوسری مخلوق پر حکومت کرنے کا اہل ہے یا نہیں اور موازنہ کر کے اُس نے انسان کو وہ سب طاقتیں بخشیں جن سے وہ مادی دنیا پر حکومت کر سکتا ہے.عَدْلٌ کے دو معنے بتائے جا چکے ہیں ایک تو تقویم کے معنے ہیں جو فَسَوّٰکَ میں آچکے ہیں پس یہاں دوسرے معنے ہی مُراد ہیں ورنہ تکرار فضول ہو جاتی ہے جو قرآن کریم کی شان کے خلاف ہے وہ دوسرے معنے موازنہ کے ہیں یعنی دوسری چیزوں کے قویٰ کو مد نظر رکھ کر اس میں طاقتیں رکھی ہیں تا کہ وہ ان پر حکومت کر سکے اور خدا تعالیٰ کا نائب ہو سکے اور اس مضمون سے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ دُنیا پر اگر کسی قوم کو حکومت ملے اور علوم سائنس پر وہ غالب آئے تو اسے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے اسے یہ قویٰ بخشے ہیں نہ کہ اُلٹا مغرور اور متکبّر ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی حکومت سے آزادی کا دعویٰ کرنے لگے اور دوسرے انسانوں پر جائز فضیلت کا مدعی بن جائے اور بجائے خدا تعالیٰ کی مغفرت حاصل کرنے کے اُس کی ناراضگی کو سُہیڑ لے.فِيْۤ اَيِّ صُوْرَةٍ مَّا شَآءَ رَكَّبَكَمیں صورت سے مراد روحانی صورت فِيْۤ اَيِّ صُوْرَةٍ مَّا شَآءَ رَكَّبَكَ اس جملہ سے اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ خدا تعالیٰ نے انسا ن کو وہ صورت دی جو اس کی پسندیدہ اور چنندہ صورت تھی یعنے صفات الٰہیہ کو اپنے اندرپیدا کرنے کی صلاحیت.کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صورت سب سے اعلیٰ ہے جسے خدا تعالیٰ کی تصویر کھینچنے کاموقع ملے اس سے زیادہ خوش قسمت اور کون ہو سکتا ہے بائبل میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا.چنانچہ لکھا ہے ’’پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہہ کی مانند بنا دیں.(پیدائش باب ۱۱ ٓیت ۲۶) اس حوالہ کا یہی مطلب ہے کہ انسان کے اندر ایسے قویٰ رکھے کہ وہ صفات الٰہیہ کو اپنے اندر جذب کر سکتا ہے اور
Page 391
گویا صفاتی طور پر خدا تعالیٰ کا مظہر بن سکتا ہے احادیث میں بھی اس مضمون کی طرف اشارہ ہے رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تَخَلَّقُوْا بِاَخْلا قِ اللّٰہِ کہ تم اللہ تعالیٰ کے اخلاق اپنے اندر پیدا کرو یعنے خدا جیسے بنو.فِيْۤ اَيِّ صُوْرَةٍ مَّا شَآءَ رَكَّبَكَ کا جملہ یا تو تفسیر سمجھا جائے گا خَلَقَكَ فَسَوّٰىكَ فَعَدَلَكَ کا یعنی اُس نے خلق وہ کیا جو اس کا پسندیدہ تھا.اس نے تسْوِیَہ وہ کیا جو اس کا پسندیدہ تھا.اس نے عَدل وہ کیا جو اس کا پسندیدہ تھا.اور یا پھر اس کے یہ معنے ہوں گے اور انہی معنوں کو مَیں نے اوپر ترجیح دی ہے کہ اس نے تمام ضروری طاقتیں انسان کے اندر پیدا کر کے اُسے وہ صورتِ روحانی بخشی جو اُس کی پسندیدہ تھی یعنی تَخَلَّقُوْا بِاَخْلَاقِ اللّٰہِ کی قابلیت اس میں پیدا کی.(تفسیر کبیر امام رازی زیر آیت واتخذوا اللہ ابراہیم...) یہاں صورتِ روحانی کے معنے جو مَیں نے لئے ہیں وہی درست ہیں اس لئے کہ صورت جسمانی کا ذکر پہلے خلق میں آچکا ہے اور جو ذکر پہلے آچکا ہے اسے دوبارہ دُہرانے کی کوئی وجہ نہیں تھی.اس جملہ میں صورتِ رُوحانی کی تکمیل کا ذکر ہے یہ معنے اس لئے بھی مرجح ہیں کہ انسان کا ناک ،کان اور منہ وغیرہ ایسی چیزیں نہیں ہیں جو خدا تعالیٰ کو پیاری لگیں.خدا تعالیٰ کے نزدیک تو انسان کی روحانی صورت ہی پسندیدہ ہوتی ہے خواہ جسمانی لحاظ سے اُس کے ناک کان کا تناسب کیسا ہی کیوں نہ ہو پس فِيْۤ اَيِّ صُوْرَةٍ مَّا شَآءَ رَكَّبَكَ کے معنے یہ ہیں کہ تمام قوتیں پیدا کرنے کے بعد ہم نے اُسے وہ رُوحانی اُصول بتائے جو ہمارے نہایت ہی پسندیدہ تھے اور جن کے ماتحت وہ ہماری صورت پر بننے کا اہل ہو گیافِيْۤ اَيِّ صُوْرَةٍ مَّا شَآءَ رَكَّبَكَ میں اس طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ جب جب جو صورت تیری ہم نے پسند کی تجھ کو بخشی جو صورت رُوحانی نوح کے زمانہ میں مناسب تھی اس کے اُصول نوح ؑ کے ذریعہ سے بتائے.جو صورت ابراہیمؑ کے زمانہ کے مطابق مناسب تھی اُس کے اصول ابراہیم ؑکے ذریعہ سے بتائے.جو صورت موسیٰ ؑ اور عیسیٰ ؑکے زمانہ کے مناسب تھی اُس کے اصول اُن کے ذریعہ سے بتائے اور جو صورت محمد رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے مناسب تھی اس کے اُصول محمدؐ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے بتائے.اسی طرح ہر قوم نے اپنے ماحول کے مطابق دنیوی ترقیات حاصل کیں اور علوم میں ایجادیں کیں.گویا ہم نے روحانی اور جسمانی علوم زمانہ اور حالات کے مطابق نازل کئے.تورات اس وقت نازل کی جب تورات کی ضرورت تھی اور قرآن اس وقت نازل کیا جب قرآن کی ضرورت تھی.علوم یونانی اس وقت نازل کئے جب انسانی دماغ اُن کو سمجھنے کی قابلیت رکھتا تھا اور علوم عربیہ اس وقت نازل کئے جب انسان ان کو سمجھنے کی طاقت رکھتا تھا اور علوم مغرب اس وقت نازل کئے جب انسان ان کو سمجھنے کی طاقت رکھتا تھا.پھر خدا تعالیٰ کے احسانات کی ناشکری کر کے دینِ حقیقی سے اجتناب اور
Page 392
بنی نوع انسان پر تفاخر کے معنے ہی کیا ہوئے.میری عمر کوئی بیس سا ل کی تھی اور میں ان دنوں لاہور میں تھا کہ میاں محمد شریف صاحب ای.اے.سی جن سے میرے دوستانہ تعلّقات تھے مجھے ایک پادری مسٹر وُڈ کے پاس لے گئے جو مشنری کالج کا پرنسپل تھا.اور کہنے لگےکہ چلو اس سے مذھبی مسائل پر گفتگو کریں مَیں نے کہا چلیں مَیں تیار ہوں.اسے اُردو پوری طرح نہیں آتی تھی اور مجھے انگریزی پوری طرح نہیں آتی تھی مگر پھر بھی ہم نے آپس میں کچھ گفتگو کر ہی لی.کچھ وہ میری مدد کر دیتا اور کچھ مَیں اس کی مدد کر دیتا اور اس طرح باتوں کا سلسلہ جاری رہا مَیں نے اس سے یہ سوال کیا کہ تم بتائو ابراہیم ؑ اور موسیٰ ؑکی نجات کس طرح ہوئی ہے.جس ذریعہ سے ان کی نجات ہو گئی ہے اسی ذریعہ سے اب بھی لوگوں کی نجات ہو سکتی ہے اس نے کہا ابراہیمؑ اور موسیٰ ؑ حضر ت مسیح پر ایمان لا چکے تھے مَیں نے کہا وہ ایمان کس طرح لا چکے تھے وہ تو حضرت مسیح سے پہلے ہوئے ہیں.قرآن کریم نے بھی اس سوال کو لیا ہے کہ حضرت ابراہیم ؑ کے متعلق یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ نصاریٰ میں سے تھے حالانکہ یہ بالکل غلط ہے وہ تو پہلے گزر چکے تھے ان کو نصاریٰ میں سے کس طرح قرار دیا جا سکتا ہے پس مَیں نے کہا کہ یہ بات تو بالکل غلط ہے.حضرت مسیح کے داؤد کی اولاد میں سے ہونے کا بے بنیاد دعویٰ اگر حضرت مسیح پر ان کے ایمان لانے کا آپ کے پاس کوئی ثبوت ہو تو اسے پیش کریں اس نے کہا دائود نے پیشگوئی کی تھی کہ اس کی اولاد سے ایک ایسا شخص ہو گا جو خدا کا بیٹا ہو گا مَیں نے کہا حضرت مسیح تو دائود کی اولاد میں سے تھے ہی نہیں یہ پیشگوئی ان پر کس طرح چسپاں ہو سکتی ہے کیونکہ انجیل میں دو جگہ مسیح کا نسب نام درج ہے (۱)متی باب ۱ آیت ۱تا ۱۸.اور پھر لوقا باب ۲ آیت ۲۳ ہر دو میں لکھا ہے کہ یوسف جس نے مریم سے شادی کی وہ دائود ؑکی اولاد میں سے تھا تو نہ معلوم یسُوع مسیح کس طرح دائود کی اولاد میں سے بن گیا.حالانکہ یوسف اس کا باپ نہ تھا.بلکہ وہ تو بے باپ پیدا ہوا.اور ماں کی طرف سے اسرائیلیوں کا نسب نامہ ہو نہیں سکتا.اصل بات یہ ہے کہ بے باپ کے پیدا ہونے کا دعویٰ ابن دائود ؑ ہونے کے دعویٰ کے بالکل خلاف ہے اور پھر اس سے ابراہیمؑ کا ایمان کہاں سے ثابت ہواپیشگوئی تو کرے دائودؑ اور ایمان ثابت ہو ابراہیم کا اس نے کہا ابراہیم ؑ کی نسبت آتا ہے کہ اُس سے اولاد کی ترقی کا وعدہ تھا مَیں نے کہا کہ مسیح ؑ تو ابراہیم کی نسل سے نہ تھے اگر اولاد کی پیشگوئی ہے تو وہ اس کی نسبت سمجھی جائے گی جو یقینانسل ابراہیمؑ سے ہے یعنے آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات نہ کہ مسیح کی نسبت جو اگر خدا کا بیٹا تھا.تو ابراہیم ؑ کا نہ تھا اور اگر ابراہیم کا بیٹا تھا تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے.آخر لمبی بحث کے بعد تنگ آکر اُس نے کہا کہ یونانی میں ایک مثل ہے کہ سوال ہر بے وقوف
Page 393
کر سکتا ہے مگر جواب دینے کے لئے عقلمند انسان چاہیے میری طبیعت بھی ان دنوں تیز تھی مَیں نے جھٹ کہا کہ مَیں تو آپ کو عقلمند سمجھ کر ہی آیا تھا اب مجھے معلوم ہوا ہے کہ یہ میری غلطی تھی.اُس نے مجھے بیوقوف بنایا تھا مَیںنے اس کا حملہ اس پر اُلٹ دیا.پس فِيْۤ اَيِّ صُوْرَةٍ مَّا شَآءَ رَكَّبَكَ میں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ہم ہر زمانہ کے لحاظ سے انسان کو تعلیم دیتے چلے آئیں ہیں کبھی ہم نے اس کی ہدایت کے لئے کوئی تعلیم نازل کی اور کبھی کوئی.اور وہ تعلیم ایسی تھی جو انسان کے مطابق حال تھی اور جس پر چل کر وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کر سکتا تھا اس کے باوجود پہلے انبیاء کی تنقیص اور دوسری اقوام کی تنقیص (جو مسیحیوں کا شیوہ ہے) خلافِ عقل ہے اسی طرح مسیح کے بعد آنے والی مکمّل تعلیم کا انکار بھی خلافِ عقل ہے.غرض الَّذِيْ خَلَقَكَ فَسَوّٰىكَ فَعَدَلَكَ.فِيْۤ اَيِّ صُوْرَةٍ مَّا شَآءَ رَكَّبَكَ میں اس طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ اے انسان پہلے تو خدا نے تجھے کرم کے ساتھ پیدا کیا یعنی تیری پیدائش کو اپنے کرم کے نیچے رکھا پھر اپنے کرم کے ساتھ تجھے ہر ایسے نقص سے جو تیری ذمّہ واریوں میں حائل ہو سکتا تھا دُور کیا.پھر دوسری چیزوں کے مقابل پر تیری تکمیل کی جب مَیں نے یہ سب کچھ کر لیا تو تُو نے اس مقصد کو ہی چھوڑ کر اَور طرف رُخ کر لیا یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ بادشاہ ایک لشکر کو تیار کرے پہلے ان کو بھرتی کرے پھر تربیت دے پھرسامان جمع کرے.پھر سامان دے کر سواریاں حوالے کرے اور جنگ کی طرف بھجوا دے مگر وہ شہر سے باہر نکل کر ایک شراب خانہ میں جمع ہو جائیں اور جوأ کھیلنے لگیں.کیا یہ لوگ اپنے آقا کو شرمندہ کرنے والے نہ ہوں گے.کیا ان سے بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ کہہ کر خطاب کرنا زجر اور افسوس کے طور پر ہو گا یا جواب سکھانے کے لئے.ہاں یہ ضرور ظاہر ہے کہ یہ افسوس اور ناراضگی ایک محسن کی ہے جو اپنے احسان جتا کر افسوس کرتا ہے کہ ہم نے کیا چاہا تھا اور تم نے کیا کر دیا.كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُوْنَ بِالدِّيْنِۙ۰۰۱۰ ایسا ہر گز نہیں (جو تم خیال کرتے ہو) بلکہ تم جزا سزا کو جھٹلاتے ہو.حَلّ لُغَات.اَلدِّیْنُ.اَلدِّیْنُکے معنی ہیں اَلْجَزَاءُ وَالْمُکَافَأَۃُ.جز ا اور بدلہ.اَلْحِسَابُ.حساب کرنا.اَلْضَائُ.فیصلہ کرنا.(اقرب)
Page 394
تفسیر.عیسائیت بعث بعد الموت کی منکر ہے فرماتا ہے کہ ہم تمہیں سچی بات بتاتے ہیں.بات یہ ہے کہ یہ خیال کہ ہم مسیح پر ایمان لا کر بخشے جائیں گے یہ تو محض ایک بہانہ ہے اصل بات یہ ہے کہ تمہیں بخشے جانے یا نہ بخشے جانے پر ایمان ہی نہیں اور قیامت کے تم قائل ہی نہیں ہو چنانچہ واقعہ یہی ہے کہ ایک عیسائی پادری کو بھی قیامت کے وجود پر حقیقی ایمان نہیں ہوتا مَیں نے دیکھا ہے جب بھی وہ قیامت پر بحث کرتے ہیں اس سے ان کا منشاء صرف اتنا ہوتا ہے کہ حضرت مسیح دوبارہ آسمان سے اُتریں گے اور یہی قیامت ہو گی ٭ ورنہ موت کے بعد جو قیامت آنے والی ہے اُس پر اُن کو کوئی یقین نہیں ہوتا.اس کی وجہ یہ ہے کہ یہودی مذہب میں قیامت کاکوئی ذکر نہیں.ہمیں اس بات پر یقین ہے کہ تورات میں قیامت کا ضرور ذکر ہو گا.اللہ تعالیٰ کا کلام اس ذکر سے خالی نہیں ہو سکتا مگر موجودہ تورات سے قیامت کے وجود کا کوئی قطعی ثبوت نہیں مِلتا.قرآن کریم میں یہ ذکر آتا ہے کہ یہودی کہا کرتے تھے ہمیں صرف چند دن عذاب دیا جائے گا.اس کے بعد ہم کو معاف کر دیا جائے گا.(البقرۃ:۸۱ ) مگر اس کے لئے بھی ہمیں پُرانی کتب میں سے حوالے محنت سے تلاش کرنے پڑتے ہیں کہ یہودیوں کا یہ عقیدہ ہوا کرتا تھا اگر قیامت کا کثرت سے یہودی کتب میں ذکر ہوتا تو اس قسم کی تلاش کی کوئی ضرورت نہ ہوتی بات یہ ہے کہ یہودی مذہب میں قیامت کا اس قدر کم ذکر کیا گیا ہے کہ یہود میں سے اکثر کا یہ خیال ہے کہ قیامت کا عقیدہ درست ہی نہیں اس وجہ سے وہ اپنا سارا زور دنیا کمانے پر صرف کر دیتے ہیں یہی حال عیسائیوں کا ہے پس فرماتا ہے كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُوْنَ بِالدِّيْنِ کیوں باتیں بناتے ہو سیدھی بات یہ ہے کہ قیامت پر تمہیں ایمان ہی نہیں.كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُوْنَ بِالدِّيْنِ کے ایک معنے یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ صفات نیک اگر استعمال ہوں تو انسا ن کے لئے سکھ کا موجب بن جاتی ہیں اور اگر بُری صفات اختیا ر کی جائیں تو وہ انسان کے لئے دُکھ کا موجب بن جاتی ہیں ٭ ان کا یہ عقیدہ ان کی کتاب میں پایا جاتا ہے’’دعائے عام ‘‘جو کرسچن نالج سوسائٹی کی طرف سے شائع ہوئی ہے.اس میں صبح کی دعاؤں کے ضمن میں لکھا ہے کہ ہر ایک دعا کرنے والا مندرجہ ذیل عبارت دہرائے ’’میں ایمان رکھتا ہوں.خدا قادر مطلق باپ پر جو آسمان و زمین کا خالق ہے اور یسو ع مسیح پر جو اس کا اکلوتا بیٹا ہمارا خداوند ہے وہ روح القدس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا.کنواری مریم سے پیدا ہوا.پیلاطوس کے عہد میں دکھ اٹھایا.مصلوب ہوا.مرگیااور دفن ہوا.عالم ارواح میں اتر گیا.تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا.آسمان پر چڑھ گیا اور خدا قادر مطلق باپ کے دہنے بیٹھا ہے وہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کے لئے آنے والا ہے.‘‘ نیز دیکھیں کتاب مذکورہ..زیر عنوان بچوں کا علانیہ بپتسمہ وہ وہاں سے (یعنی مسیح) دنیا کے آخر میں زندوں اور مردوں کی عدالت کرنے کے لئے آنے والا ہے.پس روشن کی طرح اس عبارت کے آخری فقرہ سے یہ امرواضح ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ مسیح کی آمد ثانی ہی قیامت ہے.
Page 395
رب کریم کو چھوڑ کر اُس کی دی ہوئی طاقتوں کو استعمال کرو گے تو راستہ سے بھٹک ہی جائو گے اور ایک دن اس کے بد انجام کو دیکھ لو گے.وَ اِنَّ عَلَيْكُمْ لَحٰفِظِيْنَۙ۰۰۱۱كِرَامًا كَاتِبِيْنَۙ۰۰۱۲ اور یقیناً تم پر (تمہارے خدا کی طرف سے) نگران مقرر ہیں (جو) شریف (اور) ہر بات کو لکھنے والے (ہیں) يَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْنَ۰۰۱۳ تم جو کچھ بھی کرتے ہو وہ اسے جانتے ہیں.تفسیر.اِنَّ عَلَيْكُمْ لَحٰفِظِيْنَمیں اعمال محفوظ کئے جانے کی طرف اشارہ قرآن کریم کے بعض دوسرے مقامات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانی اعمال کو محفوظ رکھا جاتا ہے.اور فرشتے اس کام پر مقرر ہیں احادیث صحیحہ میں بھی اِس کا ذکر آتا ہے پس وہ تو ہے ہی اور اس میںمسلمانوں کی کوئی تخصیص نہیں عیسائیوں کے اعمال بھی لکھے جاتے ہیں.یہودیوں کے اعمال لکھے جاتے ہیں.زرتشتیوں کے اعمال بھی لکھے جاتے ہیں اور اسی طرح دوسری اقوام کے اعمال بھی لکھے جاتے ہیں.غرض ہر کافر، دیندار، مومن ، مشرک سب کے اعمال محفوظ رکھے جاتے ہیںاور قیامت کے دن وہ ہر انسان کے سامنے پیش کئے جائیں گے.اب وائرلیس کی ایجاد نے قرآن کریم کے اس بیان کی صحت کا مزید ثبوت بہم پہنچا دیا ہے کیونکہ وائرلیس کی ایجاد نے ثابت کر دیا ہے کہ ہر حرکت جو انسان کرتا ہے خواہ وہ خفیف سے خفیف تر کیوں نہ ہو سارے جوّ میں پھیل جاتی ہے پس اس سے اتنا پتہ لگ گیا کہ انسان جو بھی حرکت کرتا ہے وہ فور ی طور پر جوّ میں لکھی جاتی ہے لکھے جانے کے معنے یہی ہیں کہ وہ اُدھر منتقل ہو جاتی ہے.اب صرف یہ سوال رہ گیا ہے کہ وہ حرکت یا وہ آواز جوّ میں کتنی دیر تک محفوظ رہتی ہے.مجھے ہمیشہ امید رہتی ہے کہ ممکن ہے کوئی زمانہ ایسا بھی آجائے کہ ہم گزشتہ لوگوں کی آوازوں کو کسی آلہ کے ذریعہ سے سُن سکیں مثلاً ہم نپولین کے مُنہ سے اس کی باتیں سُن لیں یا اگر پچھلے لوگوں کی باتوں کو ہم نہ سن سکیں تو آیندہ کے لئے ہی کوئی ایسا انتظام ہو جائے کہ ہم اُن آوازوں کو جو جوّ میں منتقل ہو جائیں دو دن چار دن دس دن کے بعد سُن سکیں.ریڈیو اور فونو گراف دونوں مل کر اب بھی یہ کام کرتے ہیں چنانچہ بادشاہ تقریر کرتا ہے تو وہ تقریر دو دو چار چار دن کے بعد دوسرے ملکوں میں سنا دی جاتی ہے تو وائرلیس اور فونو گراف دونوں نے مل کر قرآن کریم کی اِس بیان کردہ صداقت کا ثبوت مہیا کر
Page 396
دیا ہے حقیقت یہ ہے کہ انسان کا کوئی عمل ضائع نہیں جاتا وہ ضرور کوئی نہ کوئی نشان چھوڑ جاتا ہے حتیٰ کے بعض دفعہ آنے والی نسلوں پر جا کر وہ عمل ظاہر ہوتا ہے پہلے لوگ حیران ہوتے تھے کہ اعمال کس طرح لکھے جاتے ہیں مگر اب وائرلیس اور فونو گراف کی ایجاد نے ایک نیا ثبوت اس امر کا مہیا کر دیا ہے کہ انسانی اعمال محفوظ رکھے جا سکتے ہیں.قیامت کے دن ہاتھ پاؤں کا گواہی دینا قرآن کریم نے قیامت کے دن کے متعلّق جو کچھ کہا ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ اس دن ایسا ہی ہو گا انسا ن کے ہاتھ اور پیر گواہی دیں گے کہ وہ کیا کرتا رہا ہے اور کیسے اعمال اس سے سرزد ہوتے رہے ہیں ممکن ہے کوئی آلہ ایسا ہوجس پر قیامت کے دن انسان کے ہاتھ پیر اور زبان وغیرہ رکھ دئے جائیں اور یہ اعضاء تمام گزشتہ باتوں کو دہرانا شروع کر دیں گویا ایک ریکارڈ اُس وقت لگ جائے اور انسان سے کہا جائے کہ لو اب سُن لو تم کیا کچھ کرتے رہے ہو.اُس وقت وہ کہیں گالیاں دیتا نظرآئے گا.کبھی تسبیح کرتا دکھائی دے گا کہیں جھوٹ بولتا دیکھا جائے گا اور وہ اپنے ہی اعمال کو دیکھ کر شرمندہ ہو گا کہ مَیں کیا کرتا رہا ہوں.قیامت کے دن مومنوں کا سرسری حساب قرآن کریم میں مومنوں کے متعلق آتا ہے کہ اُن سے حِسَابًا یَّسِیْرًا ( انشقاق:۹) لیا جائے گا اس کا مطلب مَیں یہی سمجھتا ہوں کہ چونکہ مومن کو اللہ تعالیٰ نے معاف کرنا ہو گا اس لئے وہ اسے بدنام نہیں کرے گا اور اس کے اعمال کی تفصیلات دریافت نہیں کرے گا صرف اتنا پوچھ لے گا کہ ٹوٹل ٹھیک ہے یا نہیں.جب کہا جائے گا کہ ٹوٹل ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ کہے گا اسے لے جائو جنت میں.اس طرح اس کی بدیوں پر پردہ پڑا رہے گا لیکن جس کا ٹوٹل ٹھیک نہیں ہو گا اس کے متعلق خدا کہے گا کہ نکالو اس کا اعمال نامہ.اور اس کا ایک ایک عمل اس کے سامنے پیش کرو.اس طرح اس کی بدیاں ایک ایک کر کے سامنے لائی جائیں گی اور وہ اوّلین و آخرین میں شرمندہ اور ذلیل ہو گا.اِنَّ عَلَيْكُمْ لَحٰفِظِيْنَمیں مامور اور اس کی جماعت کی طرف اشارہ لیکن اگر اِنَّ عَلَيْكُمْ لَحٰفِظِيْنَ کِرَامًا کَاتِبِیْنَ کو عیسائیت کے لئے مخصوص قرار دیا جائے تو پھرمیں سمجھتا ہوں اس سے مراد وقت کا مامور اور اس کی جماعت ہے.فرماتا ہےوَ اِنَّ عَلَيْكُمْ لَحٰفِظِيْنَ ہم ایسے لوگ پیدا کریں گے جو تمہاری مشرکانہ باتوں کو نوٹ کریں گے اُن کو محفوظ کریں گے اور ان کو یاد رکھیں گے کیوںکہ اُن کا کام یہ ہو گا کہ وہ تمہاری ان باتوں کا ردّ کریں اور تمہارے اس زہر کا ازالہ کریں پس چونکہ وہ تمہارے ان مشرکانہ عقائد کی تردید کے لئے کھڑے ہوں گے اس لئے وہ ان باتوں کو نوٹ کرتے چلے جائیں گے یَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْنَ اور جو کچھ تم کرو گے اس سے وہ خوب واقف ہوں
Page 397
گے.یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ عیسائیوں کے تمام اعمال کو جانتے ہوں گے بلکہ مطلب یہ ہے کہ وہ اُن کے اعمال کی حقیقت سے خوب واقف ہوں گے عیسائیت دھوکا دے گی وہ اپنے بُرے کاموں کو بھی اچھی صورت میں پیش کرنے کی کوشش کرے گی مگر وہ لوگ اس دھوکا میں نہیں آئیں گے وہ ان کی نیتوںکو خوب سمجھتے ہوں گے اور جانتے ہوں گے کہ یہ لوگ اندرونی طور پر کیسے ہیں.اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِيْ نَعِيْمٍۚ۰۰۱۴وَ اِنَّ الْفُجَّارَ لَفِيْ جَحِيْمٍۚۖ۰۰۱۵ یقیناً نیکیوں میں بڑھ جانے والے لوگ (ہمیشہ)نعمت میں (رہتے) ہیں اور بدکار لوگ بھی یقینا (ہمیشہ) جہنم میں يَّصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّيْنِ۰۰۱۶ (رہتے)ہیں وہ (خصوصیت کے ساتھ)اس میں جزا سزا کے دن داخل ہوں گے.حَلّ لُغَات.اَلْاَبْرَارُ اَلْاَبْرَارُ بَرٌّ کی جمع ہے جو بَرَّ سے صفت مشبہ کا صیغہ ہے.اور بَرَّ کے معنے ہیں اَحْسَنَ الطَّاعَۃَ اِلَیْہِ وَرَفِقَ بِہٖ وَتَحَرَّی مَحَابَّہٗ وَتَوَقَّی مَکَارِھَہٗ یعنی اچھی طرح اس کی اطاعت کی اور اس کے ساتھ نرمی کا برتائو کیا نیز اس کی خوشنودی کو حاصل کرنے کی کوشش کی اوراس کی ناراضگی کی باتوںسے بچا.(اقرب) پس اَلْاَبْرَار کے معنے ہوں گے اچھی طرح اطاعت کرنے والے اور نرمی کا برتائو کرنے اور خدا تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کی کوشش کرنے والے اور اس کی ناراضگی سے بچنے کی کوشش کرنے والے.اَلنَّعِیْمُ:اَلنَّعِیْمُ اَلْمَالُ یعنی نَعِیْم کے معنے مال کے ہوتے ہیں.اور نیز اس کے معنے ہیں اَلدَّعَۃُ آرام.کہتے ہیں رَجُلٌ نَعِیْمُ الْبَالِ اور معنے ہوتے ہیں ھَادِیُٔ الْبَالِ مُرْتَاحُہٗ آسودہ حال شخص.اور نَعِیْمُ اللّٰہِ کے معنے ہیں عَطِیَّتُہٗ.اللہ کا دیا ہوا عطیہ.(اقرب) نَعِیْمٌ کے لفظ کی بناوٹ ایسی ہے کہ میں مدتوں ابتدائی عمر میں اسے جمع سمجھتا رہا.حالانکہ یہ واحد ہے جمع نہیں.مولوی محمد علی صاحب نے بھی اس کا ترجمہ ’’نعمتیں‘‘ کیا ہے.حالانکہ نَعِیْمٌ کے معنے صرف نعمت کے ہیں نعمتوں کے نہیں ہیں.مگر اس لفظ کی بناوٹ ایسی ہے کہ دھوکا لگ جاتا ہے اور غیر عرب اسے جمع سمجھنے لگ جاتا ہے.تفسیر.یہاں اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِيْ نَعِيْمٍ.وَ اِنَّ الْفُجَّارَ لَفِيْ جَحِيْمٍسے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ مومن نعیم میں ہیں اور فجّارجحیم میں ہیں.لیکن آگے چل کر فرما دیا يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّيْنِ کہ وہ جزا سزا کے وقت اس میں
Page 398
داخل ہوں گے گوصَلٰی کے معنے آگ میں داخل ہونے کے ہوتے ہیں(اقرب).اور کفّار کی نسبت یہ فرمایا گیا ہے مگرچونکہ عربی زبان کا محاورہ ہے کہ کبھی دو باتوں کے ذکر میں ایک کی تشریح کر دی جاتی ہے اور دوسری کی تشریح اس میں آجاتی ہے اس لئے یہ بھی قیاس کیا جا سکتا ہے کہ مومنوں کے داخل ہونے کے ذکر کواس لئے چھوڑ دیا ہے کہ کفّار کے جہنم میں داخلہ پر ان کے جنّت میں داخلہ کو قیاس کر لو.اس صورت میں اس آیت کے یہ معنے کئے جائیں گے کہ اگر غور سے دیکھا جائے تو معلوم ہو گا کہ مرنے کے بعد کے انتظار کی ضرورت ہی نہیں.مومن اسی دُنیا میں جنّت میں نظر آئیں گے اور کافر اسی دنیا میں دوزخ میں نظر آئیں گے یعنے وہ اطمینان جو دلوں کو سکون بخشتا ہے کفّار کے دلوں سے کوسوں دُور ہے اور باوجود دولت و ثروت رکھنے کے وہ اپنی تمام کوششوں کا نتیجہ ٹیڑھا نکلتے ہوئے دیکھتے ہیں اور اس کے بالمقابل مومن باوجود ظاہری مشکلات اور مصائب اور تباہیوں کے یقین اور امید سے پُر ہیں اور اپنے مستقبل کو شاندار اور اپنے دین کو کامیاب دیکھ کر جنّت کے مزے لے رہے ہیں.اصل بات یہ ہے کہ جس شخص کو خدا تعالیٰ پر سچا ایما ن نہ ہو اسے خواہ کتنی دولت مل جائے وہ اس کے سکون و اطمینان کا موجب نہیں بن سکتی.یورپ کے جس قدر فلاسفر ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں کہ اطمینان یورپ والوں کے دلوں سے اُڑ چکا ہے.باجود ظاہری شان وشوکت کے قلوب میں ایسی بے چینی پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے نہ انہیں دولت کا مزہ آتا ہے نہ انہیں راحت و آرام کے سامانوں میں لذت محسوس ہوتی ہے ایک جہنم ہے جو ہر وقت ان کے دلوں پر شعلہ زن رہتی ہے.لیکن مومن اس دنیا میں اپنےآپ کو جنت میں محسوس کرتا ہے.وہ دنیوی لحاظ سے مال و دولت اپنے پاس نہیں رکھتا لیکن اس کا دل مطمئن ہوتا ہے اور وہ اپنے آپ کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی جنت میں پاتا ہے.حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسّلام کا ایک مشہور واقعہ ہے.ایک مجسٹریٹ جس کے پاس آ پ کا ایک مقدمہ تھا.اس کے متعلق آپ کو یہ خبر پہنچی کہ اس نے آپ کو سزا دینے کا پختہ فیصلہ کر لیا ہے.یہ خبر خواجہ کمال الدین صاحب نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسّلام کو پہنچائی اور اس خیال کے ماتحت پہنچائی کہ نہ معلوم اب کیا ہو گا.جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسّلام نے یہ بات سنی تو آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور آپ نے فرمایا.وہ خدا تعالیٰ کے شیر پر ہاتھ ڈال کر تو دیکھے.اگر وہ ہاتھ ڈالے گا تو خود زخمی ہو جائے گا مگر ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا.تو مومن چونکہ خدا تعالیٰ پر کامل یقین رکھتا ہے اس لئے اس کے دل میں اطمینان ہوتا ہے کہ خواہ کیسی مصیبت آجائے میرا رب میری مدد کرے گا.اور اس طرح اسی دنیا میں وہ جنت میں داخل ہوتا ہے.(حیات طیبہ صفحہ ۲۶۱،۲۶۲) رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک واقعہ اس جنتِ ارضی کا بےمثال نمونہ پیش کرتا ہے.غارِ ثور میں آپ
Page 399
اور حضرت ابو بکرؓ دونوں چھپے بیٹھے تھے.دشمن اس غار کے سر پر آ پہنچا اور اس قدر قریب آگیا کہ حضرت ابو بکرؓ کو خطرہ پیدا ہو گیا کہ اب دشمن اتنا قریب ہے کہ اگر وہ ذرا جھک کر اندر کی طرف دیکھے تو وُہ ہمیں پکڑ سکتا ہے.چنانچہ رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم سے بھی اس خطرے کا اظہار کر دیا.جس پر رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم نے نہایت اطمینان کے ساتھ فرمایا لَاتَحْذَنْ اِنَّ اللّٰہَ مَعَنَا (الروض الانف زیرعنوان حدیث غار) غم مت کر خدا ہمارے ساتھ ہے.تو مومن ہر وقت جنت میں رہتا ہے اور کافر ہر وقت دوزخ میں رہتا ہے.اور اس طرح دوزخ اور جنت ہر انسان کے ساتھ ہی لگی ہوئی ہے اور وہ ہر وقت یا دوزخ میں جلتا ہے یا جنت میں اطمینان سے اپنی زندگی بسر کرتا ہے.اگر آنکھیں ہوں تو انسان اس دنیا میں یہ دوزخ اور جنت دیکھ سکتا ہے.مگر فرماتا ہے ان کفار کو یہ جہنم ابھی نظر نہیں آتی.یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مومن دوزخ میں ہیں اور وہ جنت میں لیکن گھبرائو نہیں اس کا اظہار یَوْمُ الدِّیْن کو ہو جائے گا اور ہم انہیں ایک دن اپنی آنکھوں سے یہ جہنم دکھا دیں گے جس میں وہ اب مخفی طور پر جل رہے ہیں.جب وہ دن آئے گا تو دشمن بھی کہہ اٹھے گا کہ ہاں میں جہنم میں ہوں اور مومن جنت میں.وَ مَا هُمْ عَنْهَا بِغَآىِٕبِيْنَؕ۰۰۱۷ اور وہ کسی طرح بھی اس سے (بچ کر) غائب نہیں ہو سکتے.تفسیر.فرماتا ہے.یہ پورا زور لگائیں گے کہ اس جہنم میں داخل ہونے سے بچ جائیں مگر بچ نہیں سکیں گے.آخر وہ دن آئے گا جب ان کی طاقتیں توڑ دی جائیں گی جب ان کی حکومتیں مٹا دی جائیں گی اور جب زمین اِن کے پَیروں تلے سے نکل جائے گی.چنانچہ وہ جنگ جو آج کل ہو رہی ہے یہ خود ایک جہنم ہے جس نے ان کی طاقتوں میں تزلزل پیدا کر دیا ہے اور وہ محسوس کرتے ہیں کہ اب یورپ کے تنزّل کا وقت آ رہا ہے.اور ابھی جیسا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بتایا اور میں اسے دو سال سے شائع کر چکا ہوں ایک اور عظیم الشان جنگ کی تیاریاں آسمان پر ہو رہی ہیں اور اس کے نتیجہ میں ایک وہ دن آئے گا جب وہ یہ نہیں کہیں گے کہ یورپ کے تنزّل کا وقت آرہا ہے بلکہ وہ کہیں گے یورپ کے تنزل کا وقت آگیا.قیامت کے دن تو دین حقیقی کے منکر جہنم میں جائیں گے ہی مگر اس دنیا میں بھی وہ جہنم میں داخل کر دیئے جائیں گے.وَ مَا هُمْ عَنْهَا بِغَآىِٕبِيْنَ اور یہ اس سے بچ نہیں سکیں گے.یہ اس سے بچنے کے لئے پورا زور لگائیں گے.کوشش کریں گے کہ جہنم کے دروازے ان پر بند ہو جائیں.جیسے آج کل کہیں
Page 400
لیگ آف نیشنز بنائی جا رہی ہے.اور کہیں اس آگ کو فرو کرنے کے لئے اَور تدابیر اختیار کی جا رہی ہیں.مگر یہ سب تدابیر رائیگاں جائیں گی.سب کوششیں اکارت ثابت ہوں گی.یہ اس دن سے غائب ہونا چاہیں گے مگر غائب نہیں ہو سکیں گے.اپنا سارا زور اس بات پر صرف کریں گے کہ اس جہنم سے بچ جائیں مگر بچ نہیں سکیں گے.جو کوشش بھی اس غرض کے لئے کریں گے الٹ پڑے گی اور وہ انہیں اور زیادہ اس جہنم کی طرف دھکیل کر لے جائے گی جس میں داخل ہونا ان کے لئے مقدّر ہو چکا ہے.وَ مَاۤ اَدْرٰىكَ مَا يَوْمُ الدِّيْنِۙ۰۰۱۸ اور (اے مخاطب) تجھے کس نے اس بات کا علم دیا ہے کہ جز ا سزا کا وقت کیا ہے.ثُمَّ مَاۤ اَدْرٰىكَ مَا يَوْمُ الدِّيْنِؕ۰۰۱۹ پھر (ہم تجھے کہتے ہیں کہ) تجھے کس نے علم دیا ہے کہ جزا سزا کا وقت کیا ہے.تفسیر.فرماتا ہے کس نے تم کو بتایا کہ یَوْمُ الدِّیْنِ کیا چیز ہے.ثُمَّ مَاۤ اَدْرٰىكَ مَا يَوْمُ الدِّيْنِ پھر ہم کہتے ہیں.کس نے تم کو بتایا کہ یَوْمُ الدِّیْنِ کیا چیز ہے؟ مَاۤ اَدْرٰىكَ کا لفظ قرآن کریم میں جس مقام پر بھی دوہرایا گیا ہے وہاں اس بات کی تشریح کرنے کے لئے اسے دوہرایا گیا ہے جس کا اس مقام پر ذکر آتا ہے.یہاں چونکہ يَوْمُ الدِّيْنِ کا بیان ہے.اس لئے ایک دفعہ مَاۤ اَدْرٰىكَ مَا يَوْمُ الدِّيْنِ کہنے کے بعد ثُمَّ مَاۤ اَدْرٰىكَ مَا يَوْمُ الدِّيْنِ کہنا صاف طور پر بتا رہا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ہم اس جگہ جس يَوْمُ الدِّيْنِ کا ذکر کر رہے ہیں اس سے کیا مراد ہے.یعنی يَوْمُ الدِّيْنِ تو کئی ہیں.سوال یہ ہے کہ اِن آیات میں ہم نے جس يَوْمُ الدِّيْنِ کا ذکر کیا ہے اس سے ہماری مراد کیا ہے.ورنہ اگر مَاۤ اَدْرٰىكَ کا دوبارہ آنا تشریح کے لئے نہ ہو تو پھر اس کے دوہرانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہو سکتا.کیوں کہ پہلے جو کچھ بتایا ہے وہ بھی خدا نے ہی بتایا ہے.انسان نے خود تو معلوم نہیں کیا.اور جب وہ بھی خدا نے بتایا ہے تو یہ کہنا کہ تجھے کیا پتہ کہ يَوْمُ الدِّيْنِ کیا ہے.اپنے اندر کوئی معنے نہیں رکھ سکتا.یا تو پہلی باتیں انسان نے خود معلوم کی ہوتیں.تو کہا جا سکتا تھا کہ پہلی باتیں تو تمہیں معلوم تھیں اب تمہیں کیا پتہ کہ يَوْمُ الدِّيْنِ کیا چیز ہے.مگر جب اِن باتوں کا علم بھی انسان کو خدا تعالیٰ کے بتانے کے بعد ہوا.تو اس بات کا علم بھی خدا تعالیٰ کے بتائے بغیر کس طرح ہو سکتا ہے.اس سے صاف پتہ لگتا ہے.کہ
Page 401
مَاۤ اَدْرٰىكَ مَا يَوْمُ الدِّيْنِ کو دوہرانا محض اس لئے ہے کہ تم کو کیا پتہ ہے کہ یہ يَوْمُ الدِّيْنِ جس کا ہم ان آیات میں ذکر کر رہے ہیں یہ کیا چیز ہے؟ آئو ہم تم کو بتاتے ہیں کہ جسيَوْمُ الدِّيْنِ کا ہم نے ذکر کیا ہے اس سے ہماری مراد کیا ہے؟ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْـًٔا١ؕ (یہ وقت) اس دن (ہو گا) جس میں کوئی جان کسی جان کو فائدہ پہنچانے کے لئے کوئی اختیار نہ رکھے گی.وَ الْاَمْرُ يَوْمَىِٕذٍ لِّلّٰهِؒ۰۰۲۰ اور سب فیصلہ اس دن اللہ ہی کے ہاتھ میں ہو گا.تفسیر.یہاں نَفْسٌ لِّنَفْسٍ سے مَیں اپنے ذوق کے مطابق پھر وہی نفسِ عیسائیت مراد لیتا ہوں جس کا عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَاَخَّرَتْ میں ذکر کیا گیا تھا کہ یورپ کی جتھے بازیاں اس کے کسی کام نہیں آئیں گی.وہ جتھے بنا بنا کر اور لیگ آف نیشنز قائم کر کے اس عذاب سے بچنے کی کوشش کریں گے.مگر نہ ان کے جتھے ان کے کام آئیں گے اورنہ ان کی سوسائیٹیاں ان کو اس عذاب سے بچا سکیں گی.عیسائیت کی بنیاد چونکہ کفا رہ پر ہے اس لئے يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْـًٔا میں اس امر کی طرف بھی اشارہ ہے کہ تمہارا کفارہ دھرے کا دھرا رہ جائے گا اور وہ تمہارے کسی کام نہیں آئے گا.وَ الْاَمْرُ يَوْمَىِٕذٍ لِّلّٰهِکے معنے اس دنیا کے لحاظ سے وَ الْاَمْرُ يَوْمَىِٕذٍ لِّلّٰهِ قیامت کے لحاظ سے تو اس آیت کا مفہوم ظاہر ہی ہے.اس دنیا کے لحاظ سے اِس آیت کے یہ معنے ہیں کہ اُنیس سو سال سے عیسائی یہ دعا کرتے چلے آئے ہیں کہ اے خدا تیری بادشاہت جس طرح آسمان پر ہے اسی طرح زمین پر بھی آئے(متی باب ۶ آیت ۱۰).مگر انیس سو سال تک خدا کی بادشاہت زمین پر لانے والے اپنے مقصد میں ناکام رہے اور وہ خدا تعالیٰ کی بادشاہت کو زمین پر اس طرح نہ لا سکے جس طرح وہ آسمان پر قائم ہے.لیکن جب کبھی بھی وہ اس امر میں ناکام رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ایک دوسری جماعت کو کھڑا کر دے گا جو امر الٰہی کو آسمان سے زمین پر لانے میں کامیاب ہو جائے گی اور خدا تعالیٰ کی بادشاہت کو زمین پر قائم کر کے دکھا دے گی.گویا جس کام کو یہ لوگ اُنیس سو سال میں نہ کر سکے وہ کام ہماری ایک اَور جماعت کر کے دکھا دے گی اور اللہ تعالیٰ کا حکم زمین پر جاری ہو جائے گا.خدا تعالیٰ مجسّم نہیں کہ وہ دنیا میں آجائے.خدا تعالیٰ کے آنے سے مراد اس کی بادشاہت کا قیام ہوتا ہے.اور
Page 402
اس آیت میں یہی خبر دی گئی ہے کہ آخر وہ بادشاہت قائم ہو جائے گی.حق آ جائے گا اور باطل بھاگ جائے گا.اس طرح وہ مایوسی جو پہلی آیتوں کے مطالعہ سے دلوں میں پیدا ہو سکتی تھی.اللہ تعالیٰ نے اس کو دُور کر دیا اور مومنوں سے کہہ دیا کہ ڈرو نہیں.قرآن کا زمین سے اٹھ جانا.ایمان کا ثریّا پر چلا جانا.کفر کا دنیا پر غالب آ جانا.شرک اور معصیت کا لوگوں میں پھیل جانا.رسول کریم صلے اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کا روشن چہرہ لوگوں سے اوجھل ہو جانا.صحابہؓ کی اتباع کا شوق دلوں سے جاتے رہنا تمہارے دلوں میں مایوسی مت پیدا کرے.ہم تمہیں بشارت دیتے ہیں کہ اَلْاَمْرُ يَوْمَىِٕذٍ لِّلّٰهِ.گو عیسائی فتنہ بڑا سخت ہے.مگر ہم قرآن اور اسلام کی حکومت دنیا میں قائم کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں.اور دنیا کی کوئی طاقت ہمارے اس فیصلہ کو بدل نہیں سکتی.ہم پھر اسلام کو قائم کریں گے.پھر قرآن کو قائم کریں گے.پھر محمد رسول اللہ صلے اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کی حکومت ساری دنیا میںقائم کریں گے.اس لئے تمہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں.تمہارے لئے مایوسی کا کوئی مقام نہیں.بلکہ خوشی اور مسرّت کا مقام ہے.کہ اسلام پھر اپنی گم گشتہ عزت کو حاصل کرے گا.اور ساری دنیا پر غالب آ جائے گا.خ خ خ خ
Page 403
سُوْرَۃُ التَّطْفِیْفِ مَکِّیَّۃٌ سورۃ تطفیف.یہ سورۃ مکی ہے وَھِیَ سِتٌّ وَّ ثَلٰثُوْنَ اٰیَۃًدُوْنَ الْبَسْمَلَۃِ اور بسم اللہ کے علاوہ اس کی چھتیس ۳۶آیات ہیں.سورۃ تطفیف مکی ہے اس سورۃ کے مکّی یا مدنی ہونے کے متعلق اختلاف پایا جاتا ہے.بعض لوگوں کا خیا ل ہے کہ اس سورۃ کی پہلی چھ آیات مدنی ہیں.گویا يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَتک مدنی آیات ہیں اور بعض کے نزدیک یہ ساری سورۃ ہی مدنی ہے (اتقان فی علوم القرآن ،الدرمنثور ) لیکن اکثر مفسّرین کی یہ رائے ہے کہ یہ سورۃ مکی ہے.چنانچہ ہمارے ملک میں جو قرآن شریف شائع ہوتے ہیں اُن پر سُوْرَۃُ التَّطْفِیْفِ مَکِّیَّۃٌ ہی لکھا ہوتا ہے.جن یوروپین محققین نے اس پر بحث کی ہے تعجب ہے کہ اپنے اصول کے خلاف انہوں نے بھی اسے مکّی قرار دیا ہے حالانکہ اُن کے معترضانہ میلانات کو مدنظر رکھتے ہوئے اُنہیں اسے زبردستی بھی مدنی قرار دینا چاہیے تھا خصوصاً جبکہ بعض مفسّرین کی تصدیق انہیں حاصل ہو گئی تھی.لیکن یہ خدا تعالیٰ کا تصرّف ہے کہ انہوں نے اِسے مکی ہی قرار دیا ہے اور پھر مکی بھی ابتدائی سورتوں میں سے.چنانچہ نولڈکے NOLDEKE جرمن پروفیسر اور میور MUIRدونوں اِسے چوتھے سال قبل ہجرت کے قریب کی بتاتے ہیں (تفسیر القرآن از وہیری جلد۴ صفحہ ۲۲۶)اور یہی رائے درست ہے کہ یہ مکّی اور ابتدائی زمانہ کی ہے.سورۃ کو مکی یا مدنی قرار دئیے جانے کے اصول اور ان کی حقیقت سورتوں کے مکی یا مدنی قرار دینے کی بنیاد اول تو روایات پر ہوتی ہے جن کو بیان کرنے والے بعض دفعہ تو اُس وقت کے مسلمان ہوتے ہیں جس وقت وہ سورۃ نازل ہوئی اور وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے علم میں یہ سورۃ فلاں وقت نازل ہوئی ہے اور بعض لوگ اپنا علم نہیں بتاتے بلکہ اس امرپر قیاس کر کے رائے لگاتے ہیں کہ ہم فلاں وقت مدینہ میں گئے تھے اور یہ سورۃ پڑھی گئی تھی اس لئے اُس وقت کی نازل شدہ ہے.حالانکہ پہلے کی نازل شدہ سورۃ بھی تواُس وقت پڑھی جا سکتی ہے.تیسرےؔ بعض واقعات جو سورۃ میں مذکور ہوں اُن کی بناء پر زمانہ نزول مقرر کیا جاتا ہے.چوتھے بعض الفاظ کی بناء پر جن کی نسبت مفسرین یا مستشرقین یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ صرف مکی یا مدنی زمانہ میں استعمال ہوتے تھے فیصلہ کیا جاتا ہے کہ سورۃ
Page 404
مکی ہے یا مدنی.پانچویں تفصیلی مسائل کی بناء پر مستشرقین سورتوں کو مدنی قرار دیتے ہیں کیونکہ اُن کے نزدیک تفصیلی مسائل مدنی سورتوں میں ہوتے ہیں.چھٹے طرز کلام کی بناء پر فیصلہ کیا جاتا ہے.مثلاً لمبی آیتیں ہوں تو مستشرقین اُن کو مدنی اور چھوٹی آیات ہوں تو مکی قرار دیتے ہیں.ساتویںیہود کا ذکر آجائے تو مستشرقین کہہ دیتے ہیں کہ یہ مدنی سورۃ ہے.آٹھویںاگر کفار کے خلاف کوئی سخت حکم آجائے تو کہہ دیتے ہیں کہ یہ مدنی ہے.ان دلیلوں میں سے صرف پہلی دلیل یقینی ہے.باقی صرف ظنی ہیں اور انہیں مستشرقین اسلام کے خلاف حربہ کے طور پر استعمال کرنے سے کبھی نہیں چُوکتے.اور بعض دلائل ان میں سے قطعًا غلط بھی ہیں مگر یہ موقعہ ان پر بحث کا نہیں ہے.خود مستشرقین کا اپنا طریق عمل ان دلائل کے خلاف پڑتا ہے کیونکہ بعض دفعہ وہ خود (جب اُن کا مطلب اس طرح پورا ہوتا ہو) ان دلائل کے خلاف رائے دے جاتے ہیں جیسا کہ مختلف مقامات پر اس کی طرف تفسیر میں اشارہ ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہے گا.درحقیقت مستشرقین بعض دلائل سے یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ قرآن کریم کی تعلیم رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں اور یہودیوں سے مل کرسیکھی تھی.پس اگر یہ ثابت ہو جائے کہ مکی سورتوں میں عیسائیوں اور یہودیوں کی تعلیمات کا کوئی تفصیلی ذکر نہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے ثابت ہوا کہ مدنی سورتوں میں اِن کا اس لئے ذکر ہے کہ آپ نے مدینہ میں غیروں سے مل کر ان باتوں کو سیکھ لیا.جو مسلمان مفسرین ان امور میں کمزور دلائل کی بناء پر رائے قائم کرتے ہیں.وہ نا دانستہ طور پر عیسائیت کو تقویت پہنچا دیتے ہیں حالانکہ یہ اصول بالکل قیاسی ہیںاور تاریخی مسئلہ کو قیاس سے طے کرنا غلط طریق عمل ہوتا ہے صرف قطعی تاریخی شہادت یا داخلی قیاس ہی ایسے موقعہ پر صحیح ہوتے ہیں اور وہ بھی اُس صورت میں جبکہ خود قرآن کا دوسرا مضمون اُن کی تائید کرتا ہو.یہ مضمون بہت لمبا ہے جس کو اس وقت بیان نہیں کیا جا سکتا.سورتوں کے مکی یا مدنی ہونے کے متعلق صحیح رسالہ لکھے جانے کی ضرورت ضمنًا میں نے اس طرف توجہ دلا دی ہے ورنہ یہ مضمون تقاضا کرتا ہے کہ اس پر ایک مستقل رسالہ لکھا جائے.سورتوں کے مکّی یا مدنی ہونے کے متعلق جہاں تک روایاتِ صحیحہ کا تعلق ہے یا تاریخی تحقیق کا تعلق ہے ان کو ہم تسلیم کرتے ہیں لیکن جو حصہ قیاس سے تعلق رکھتا ہے اس میں بعض غلط اصول قرار دےدیئے گئے ہیں جن کی وجہ سے غلط نتائج پیدا ہوتے ہیں اور اُن غلط نتائج سے دشمنانِ اسلام ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں انہیں تسلیم کرنے کو ہم تیار نہیں.بہرحال یہ مضمون ایک مستقل رسالہ کا طالب ہے تا کہ تفصیلی طور پر بحث کر کے یہ بتایا جائے کہ قرآن کریم کی ترتیب کے متعلق جو استدلال کئے جاتے ہیں اُن میں کیا کچھ غلطیاں ہیں اور کن بنیادوں پر ان نقائص کا ازالہ کیا جا سکتا ہے.اللہ تعالیٰ ہماری جماعت
Page 405
میں سے کسی کو توفیق دے یا خود مجھے ہی توفیق دے دے تو اس کے متعلق ایک مستقل رسالہ لکھا جانا ضروری ہے درحقیقت امام سیوطی نے جو اتقان کتاب لکھی تھی وہ اس سلسلہ کی پہلی کوشش تھی جس میں اُن سے بہت سی غلطیاں بھی ہوئیں.اب ضرورت ہے کہ ایک حقیقی اتقان لکھی جائے کیونکہ اتقان کے معنے ہیں مضبوط اور پکّی باتیں.لیکن غلطی سے اُس میں کچھ کچی باتیں بھی آ گئی ہیں اس لئے ضروری ہے کہ حقیقی معنوں میں ایک اتقان کتاب لکھی جائے جس میں صحیح اصول پر اس مسئلہ کو بیان کیا جائے اور غلط باتوں کی تردید کی جائے.ترتیب.پہلی سورۃ سے سورۃ التطفیف کے دو تعلق پہلی سورۃ سے اس سورۃ کے دو تعلق ہیںایک قریب کا اور ایک بعید کا.یعنی ایک تو قریب مضمون سے اس کا تعلق ہے اور ایک سلسلۂ کلام سے اس کا تعلق ہے.میرا تجربہ یہی ہے کہ قریبًا ہر سورۃ کا دوسری سورۃ سے تعلق ہوتا ہے اور پھر میرے علم کے مطابق ہر سورۃ کا دوسری سورۃ سے ایک تعلقِ قریب ہوتا ہے اور ایک تعلقِ بعید ہوتا ہے یعنی ایک تعلق تو ایسا ہوتا ہے جو اسے پہلی سورۃ کی آخری آیتوں سے ملا دیتا ہے لیکن ایک تعلق ایسا ہوتا ہے جو سلسلۂ مضمون سے متعلق ہوتا ہے پھر آگے یہ تعلق دو قسم کا ہوتا ہے.ایک تعلق تو سورۃ کا قریب کی سورۃ یا اس کے ساتھ کی سورۃ سے ہوتا ہے اور مضمون میں ایک تسلسل پایا جاتا ہے اور ایک تعلق ایسا ہوتا ہے جو چھ چھ سات سات بلکہ دس دس سورتیں پیچھے جا کر اس سورۃ کو پچھلی سورتوں سے ملا دیتا ہے یہ بھی ایک ایسا مضمون ہے جو خدا تعالیٰ کے فضل سے ایک حد تک میں نے سمجھا ہے.سورتوں کے آپس کے قریب کے تعلقات اور تسلسل مضمون کے اعتبار سے اُن کے آپس کے تعلقات بالعموم میں نے اخذ کئے ہیں لیکن مجھ پر اثر یہ ہے کہ سورتوں کا ایک تعلق بعید یا ابعد بھی ہوتا ہے.مجھے اس کے متعلق ایسی فرصت نہیں ملی کہ اس مضمون کو مکمل طور پر حل کر سکوں.چونکہ میرے پاس پہلے ہی کاموںکی کثرت ہے اور اس کے لئے فرصت نکالنا بہت مشکل ہے اِس لئے میںاس مضمون کو حل کرنے کی ایک تجویز بتادیتا ہوں.سورتوں کے آپس میں تعلقات کو سمجھنے کا ایک طریق میری رائے یہ ہے کہ قرآن کریم کی سورتیں الگ الگ خوشخط لکھوا کر اُن کے چارٹ بنوائے جائیں اور پھر اُن الگ الگ ٹکڑوں کو انسان ایک کمرے میں لٹکا دے اور فرصت کے وقت اُن کو دیکھتا رہے.اس کے نتیجہ میں اُسے سورتوں کے باہمی تعلقات کا ضرور نشان مل جائے گا جب ایک چارٹ حل ہو جائے تو دوسرے پر غور کرنا شروع کر دے.دوسرا حل ہو جائے تو تیسرے کو مدنظر رکھ لے.جس شخص کو فرصت ہو اور قرآن کریم پر غور کرنے کا وہ شوق رکھتا ہو اگر وہ ایسا کرے تو اس کو بہت کچھ فائدہ پہنچ سکتا ہے.اس سورۃ کا پہلی سورۃ سے قریب کا تعلق تو یہ ہے کہ سورۂ انفطار کے آخر میں فرمایا تھا يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ
Page 406
لِّنَفْسٍ شَيْـًٔا١ؕ وَ الْاَمْرُ يَوْمَىِٕذٍ لِّلّٰهِ گویا وہاں ایک محاسبے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا تھا اور بتایا تھا کہ تمہیں یہ گھاٹا اپنے پاس سے پورا کرنا پڑے گا دوسرا کوئی شخص اس کمی کو پورا نہیں کر سکتا.پس چونکہ وہاں محاسبے کا ذکر تھا اس لئے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ.میں اللہ تعالیٰ نے ادھر اشارہ فرما دیا کہ جس نے حساب دینا ہو اس کو اپنا حساب بالکل صاف رکھنا چاہیے.یہی بات ہے جو حضرت مسیح ناصری ؑ نے کہی مگر مسیحیوں کی نظر سے پوشیدہ ہو گئی.حضرت مسیح ؑ نے کہا ’’مبارک وے جو رحم دل ہیں کیونکہ اُن پر رحم کیا جائے گا‘‘ (متی باب ۵ آیت ۷) اسی طرح ایک دوسری جگہ ان کی بات بیان کی گئی ہے.لکھا ہے ’’اگر تم آدمیوں کے گناہ بخشو گے تو تمہارا باپ بھی جو آسمان پر ہے تمہیں بخشے گا پر اگر تم آدمیوں کو اُن کے گناہ نہ بخشو گے تو تمہارا باپ بھی تمہارے گناہ نہ بخشے گا‘‘ (متی باب ۶ آیت ۱۴،۱۵) اسی حقیقت کو اللہ تعالیٰ اس جگہ بیان فرماتا ہے کہ تم نے خدا کے سامنے پیش ہونا ہے اگر تم وہاں گھاٹے سے بچنا چاہتے ہو تو بندوں کو بھی کسی قسم کا گھاٹا نہ دو.عجیب بات یہ ہے کہ عیسائیوں کو جو کچھ تعلیم دی گئی تھی اس کے بالکل اُلٹ انہوں نے نتیجہ نکال لیا یعنی اُنہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم تو رحم کر سکتے ہیں لیکن خدا رحم نہیں کر سکتا حالانکہ خدا ہمارے رحم کو اپنے رحم کی وجہ قرار دیتا ہے اور حضرت مسیح ؑ بھی یہی فرماتے ہیں کہ تم لوگوں پر رحم کرو تا آسمانی باپ تم پر رحم کرے.گویاہمیں رحم کرنے کی اس لئے ضرورت ہے تاکہ خدا ہم پر رحم کرے مگر دوسری طرف عیسائیت یہ کہتی ہے کہ تم تورحم کر سکتے ہو لیکن خدا رحم نہیں کر سکتا.یہ کتنی متضاد تعلیم ہے جو عیسائیت میں پائی جاتی ہے.بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارا معاملہ خدا تعالیٰ کے ساتھ ہے اگر تم چاہتے ہو کہ خدا تعالیٰ تمہارے ساتھ نرمی اور محبت کا سلوک کرے تو تم بھی اس کے بندوں کے ساتھ نرمی اور محبت کے ساتھ پیش آئو.يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْـًٔا١ؕ وَ الْاَمْرُ يَوْمَىِٕذٍ لِّلّٰهِ میں خدا تعالیٰ کے ساتھ انسان کے معاملے کا ذکر کیا گیا ہے اوروَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ.میں بنی نوع انسان کے باہمی معاملات کا ذکر کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ تم لوگوں کے ساتھ ٹھیک ٹھیک معاملہ کیا کرو تا کہ خدا تمہارے ساتھ نیک سلوک کرے.گویا سورۂ انفطار کا آخری حصہ حضرت مسیح ناصریؑ کے ایک قول کی تائید کرتا ہے اور اس سورۃ کا پہلا حصّہ حضرت مسیح ناصریؑ کے دوسرے قول کی تائید کرتا ہے.اس سورۃ کا پہلی سورتوں سے تعلق بلحاظ مضمون ترتیبِ بعید یہ ہے کہ گزشتہ دو سورتوں سے عیسائیت کا ذکر
Page 407
ہو رہا ہے اور عیسائیوں کے اعمال کے دو حصّے بڑے خطرناک ہیں.وہ حصہ بھی جو مذہب کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور وہ حصہ بھی جو غیر اقوام کے ساتھ تعلق رکھتا ہے مذہبی نقطۂ نگاہ سے اُن کے اعمال کی بُرائی اس سے ظاہر ہے کہ وہ شرک کا ارتکاب کرتے ہیں مسیح ناصریؑ کو خدا تعالیٰ کا بیٹا قرار دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی توحید کو مٹا رہے ہیں.اسی کی طرف پہلی سورۃ میں اشارہ کیا گیا تھا کہ اِذَا السَّمَآءُ انْفَطَرَتْ یعنی ہم نے جو کہا تھا کہ اِن لوگوں کے شرک سے قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے وہ وقت آگیا ہے اور انہوں نے اس قدر شرک سے کام لیا ہے کہ آسمان واقعہ میں پھٹ گیا ہے.پس اُن کے اعمال کا ایک حصّہ تو یہ ہے.دوسرا حصّہ اُن کے اعمال کا آپس کی جتھہ بندی اور باقی تمام غیر قوموں سے انتہائی بد سلوکی سے پیش آنا ہے.پس پہلی سورۃ میں عیسائیوں کی مذہبی بُرائی بتانے کے بعد اس سورۃ میں یہ بیان کرتا ہے کہ اُن کا معاملہ دوسری اقوام سے بہت بُرا ہو گا.وہ اُن کو لوٹیں گے.اُن کے معاہدات اور معاملات ہمیشہ دو رُخے ہوں گے.آپس میں اُن کا اور سلوک ہو گا اور دوسری اقوام سے اُن کا اور سلوک ہو گا.غرض تطفیف عیسائیت کا ایک نہایت ہی نمایاں پہلو ہے.اِن سے پہلے تاریخ میں قوموں کی جتھہ بندی کی اور کوئی مثال ایسی نہیں ملتی جیسی یوروپین اقوام میں دکھائی دیتی ہے.یہ لوگ دہریہ ہیں.عقائد کے اعتبار سے ان کا عیسائیت سے کوئی تعلق نہیں لیکن جہاں عیسائیت کا سوال آجائے وہاں یہ ضرور اس کا لحاظ کر جائیں گے.اور دہریہ ہوتے ہوئے بھی عیسائیت کی رعایت کریں گے.جرمن ہیں وہ بھی دہریہ ہیں مگر عیسائیوں سے اُن کا معاملہ اَور رنگ کا ہو گا.اور دوسری اقوام سے اَور رنگ کا ہو گا.وہ یہودیوں پر سخت سے سخت ظلم کریں گے مگر عیسائیوں کا سوال آ جائے تو اُن سے نرمی کا برتائو کریں گے.یہی حال انگریزوں اور امریکن باشندوں کا ہے اُن کے اندر کوئی مذہب نہیں لیکن عیسائیت کے نام کا مٹنا وہ برداشت نہیں کر سکتے.اب لڑائی ہو رہی ہے مسلمانوں اور ہندئووں کو وہ اس جنگ میں کٹوا رہے ہیں مگر کہہ یہ رہے ہیں کہ ہم کرسچن سویلزیشن قائم کریں گے حالانکہ کرسچن سویلزیشن کا کوئی مفہوم نہیں سوائے زمانہ حاضرہ کی تہذیب کے اور عیسائیت سےاس کادُور کا بھی تعلق نہیں.مگر وہ کہتے یہی ہیں کہ ہم عیسائی تہذیب دنیا میں قائم کرنے کے لئے یہ سب کچھ کر رہے ہیں.پھر یہ عجیب معاملہ ہے کہ عیسائی قومیں آپس میں بھی ایک دوسرے پر ظلم کرتی ہیں مگر اس ظلم کا دائرہ محدود ہوتا ہے گویا انہوں نے ظلم کے دو دائرے بنا لئے ہیں.ایک ظلم عیسائیت پر اور ایک ظلم غیر عیسائیت پر.جب غیر پر ظلم ہو تو تمام عیسائی قومیں اکٹھی ہو جاتی ہیں اور آپس کے تعلقات کو بھلا دیتی ہیں پس یہ لوگ دو ظلم کر رہے ہیں ایک خدا پر ظلم ہے اور ایک اس کی مخلوق پر ظلم ہے.چونکہ مخلوق پر ظلم عیسائیوں کے اعمال کا دوسرا حصہ تھا اس لئے اللہ تعالیٰ نے
Page 408
اس کے لئے دوسرا باب باندھ دیا یعنی دوسری سورۃ میں اس کا ذکر کیا.جیسے زمانہ کے تغیّرات میں سے عیسائیت کا تغیّر اتنا اہم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے ایک الگ سورۃ نازل فرما دی.اسی طرح عیسائیت کے دو بہت بڑے ظلم تھے.ایک وہ ظلم تھا جس کا خدا سےتعلق تھا اور ایک وہ ظلم تھا جس کا مخلوق کے ساتھ تعلق تھا.خدا تعالیٰ پر عیسائیت کا جو ظلم تھا اس کو سورۂ انفطار میں بیان کر دیا گیا اور جو ظلم انسانوں پر تھا اس کو سورۂ تطفیف میں بیان کر دیا گیا.بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۰۰۱ (میں) اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا (اور) بار بار رحم کرنے والا ہے (شروع کرتا ہوں) وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَۙ۰۰۲ وزن میں کمی کرنے والوں کے لئے عذاب (ہی عذاب) ہے.حَلّ لُغَات.وَیْل.کلمہ وَیْل عذاب کے لئے اور دکھ کے لئے بیان کیا جاتا ہے(اقرب).اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَیْلٌ یعنی عذاب ہو گا.دکھ ہو گا.مُطَفِّفِیْن لِلْمُطَفِّفِیْن: مطفّفین کے لئے.مُطَفِّفِیْنَ مُطَفِّفٌ سے جمع کا صیغہ ہے اور مُطَفِّفٌ طَفَّفَ سے اسم فاعل ہے.طَفَّفَ الْمِکْیَالَ کے معنے ہیں نَقَصَہٗ اس کو کم ماپ کر دیا.اور طَفَّفَ الْوَزْنَ کے بھی یہی معنے ہیں کہ نَقَصَہٗ اس کو کم وزن کر کے دیا.گویا تطفیف کا لفظ کَیْل کے لئے بھی بولا جا سکتا ہے اور وزن کے لئے بھی بولا جا سکتا ہے.نیز کہتے ہیں طَفَّفَ عَلَی عِیَالِہٖ اَیْ قَتَّرَ عَلَیْھِمْ اس نے اپنے عیال کو تنگ رزق مہیا کیا اور کہتے ہیں طَفَّفَ عَلَی الرَّجُلِ اَیْ اَعْطَاہُ اَقَلَّ مِمَّ اَخَذَ مِنْہُ یعنی جو کچھ اس سے لیا تھا اُس سے کم اس کو دیا (اقرب) پس مُطَفِّفٌ کے معنے ہوں گے کسی کو وزن یا ماپ میں کم دینے والا.تفسیر.یورو پین اقوام کا غیر قوموں کے حقوق کو غصب کرنے کا خلاصہ یہ یوروپین اقوام کا خاصہ ہے کہ وہ غیر قوموں کے حقوق کو غصب کرنا اپنا کمال سمجھتے ہیں.اُن کی ساری سیاسی اور اقتصادی پالیسی کا بنیادی اصول یہی ہے کہ غیر قوموں کے حقوق کوغصب کر لیا جائے.حضرت خلیفہ اول رضی اللہ عنہ ایک بات بیان فرمایا کرتے تھے جس کا میری طبیعت پر بڑا گہرا اثر ہے آپ فرماتے تھے دنیا میں کوئی قوم سود لے کر ذلیل ہو جاتی ہے اور کوئی قوم سود دے کر ذلیل ہو جاتی ہے مگر یہ عیسائی قوم ایسی ہے کہ یہ سود لے کر بھی لُوٹتی ہے اور سود دے کر بھی لُوٹتی
Page 409
ہے.آپ فرماتے تھے کہ سُود لے کر لوٹنا تو ان کے بنکوں سے ظاہر ہے اور سُود دے کر دوسروں کو لُوٹ لینے کے ذکر میں آپ اودھ کی حکومت کی مثال دیا کرتے تھے.بعد میں مَیں نے حوالے دیکھے تو آپ کی یہ بات درست معلوم ہوئی کہ واقعہ میں انہوں نے اودھ کی حکومت کو سود دے کر لوٹا ہے انہوں نے لوگوں میں اعلان کر دیا کہ کلکتہ بنک میں اگر اپنا روپیہ جمع کرا دو تو تمہیں بڑا نفع ملے گا.چنانچہ لوگوں نے روپیہ جمع کرانا شروع کر دیا اور انہوں نے ان کو خوب سود دیا یہاں تک کہ عورتوں نے اپنے زیورات بیچ بیچ کر روپیہ اس بنک میں جمع کرانا شروع کر دیا اور سمجھا کہ انگریز بڑے خیر خواہ ہیں یہ تو ہمیں خوب منافع دیتے ہیں جب اودھ کے بادشاہ سے انگریزوں کا اختلاف پیدا ہوا اور انگریزی فوجیں لکھنؤ کی طرف بڑھنی شروع ہوئیںتو امراء نے بادشاہ کو انگریزی فوج کے اس حملہ سے بالکل غافل رکھا جب انگریزی فوجیں لکھنؤ کے قریب آئیں تو اودھ کے تمام امراء کو نوٹس مل گیا کہ اگر تم نے ذرا بھی حرکت کی تو تمہارا بنک میں جس قدر روپیہ ہے وہ سب ضبط کر لیا جائے گا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ خاموش بیٹھے رہے اور بادشاہ کو تب پتہ لگا جب انگریزی فوجیں شہر کے دروازہ پر پہنچ گئیں.بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بادشاہ کو غافل رکھنے کے لئے امراء نے ناچ کی تحریک کر دی تھی چنانچہ وہ اسی ناچ میں مشغول رہا یہاں تک کہ انگریزی فوجیں اُس کے سر پر جا پہنچیں.(حقائق الفرقان زیر آیت الذین یأکلون الربا..) غرض عیسائی قوم ایسی ہے جس نے روپیہ لے کر بھی دوسروں کو لوٹا ہے اور روپیہ دے کر بھی دوسروں کو لوٹا ہے یہ صحیح معنوں میں مُطَفِّف ہیں اور ہر بات میں اپنا حق فائق رکھتے ہیں.لیکن اگر دوسروں کے حق کا سوال ہو تو اُس پر سو سو اعتراض کر دیتے ہیں آخر یہ موٹی بات ہے کہ وجہ کیا ہے کہ ساری دنیا اُن کے قبضہ میں آگئی.کون سے جائز دلائل اور معقول وجوہ تھے جن کی بناء پر انہوں نے اتنا بڑا تسلّط حاصل کر لیا کہ چینؔ ہے تو اس میں ان کا دخل ہے.ہندوستانؔ ہے تو وہاں ان کا دخل ہے.افغانستانؔ ہے توا س پر اُن کا دبائو ہے.اسی طرح بخاراؔ کیا اور چینیؔ ترکستان کیا اور کاکیشیاؔ کیا اور جارجیاؔ کیا ہر جگہ ان کا دخل ہے.عربؔ ہے تو وہاں ان کا تصرّف ہے.ترکیؔ ہے تو اس کے معاملات میں ان کا دخل ہے.مصرؔ ہے تو وہ ان کے قبضہ میں ہے.افریقہؔ ہے تو وہ ان کے ماتحت ہے آخر لوگوں نے کون سے قصور کئے تھے کہ جن کی وجہ سے یہ جہاں بھی گئے وہ مغلوب ہوتے گئے اور یہ غالب آتے چلے گئے.اس کی وجہ سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ زبردست کاٹھِینگا سر پر.اِن کی مثال بالکل اس بندر کی سی ہے جو دو بلّیوں کا پنیروزن کرنے کے بہانہ سے کھا گیا تھا.کہتے ہیں کہ دو بلّیوں نے کہیں سے پنیر کا ایک ٹکڑہ چُرایا جس پر اُن دونوں میں لڑائی ہو گئی.ایک کہتی تھی کہ مَیں اتنا حصّہ لوں گی اور دوسری کہتی تھی کہ مَیں اتنا حصّہ لوں گی.آخر انہوں نے ایک بندر سے کہا
Page 410
کہ یہ پنیز ہم میں بانٹ دو.بندر نے ترازو لیا اور اندازاً اُسے دو ٹکڑوں میں کاٹ کر الگ الگ پلڑے میں رکھ دیا.جب اُس نے ترازو کو اٹھایا تو دونوں پلڑوں میں کچھ فرق پڑ گیا.اس پر بجائے دوسری طرف سے چھوٹا سا ٹکڑہ کاٹ کر کسی ہلکے پلڑے میں رکھنے کے اُس نے مُنہ مار کر بھاری ٹکڑے میں سے ایک بڑا سا ٹکڑہ کاٹ لیا.اور جب دوبارہ دوسرا پلڑا جھک گیا تو اُس طرف سے ایک بڑا سا ٹکڑہ کاٹ کر مُنہ میں ڈال لیا اور اسی طرح وہ کبھی ایک طرف سے پنیر کا ٹکڑہ کاٹ کر کھا لیتا اور کبھی دوسری طرف سے.یہاں تک کہ بہت تھوڑاسا پنیر رہ گیا.اتنے میں بلّیوں کو بھی سمجھ آ گئی کہ ہم نے یہ کیا حماقت کی کہ ایک بندر کے سپرد پنیر کر دیا وہ تو اسی طرح تمام پنیر کھا جائے گا چنانچہ بلیوں نے کہا کہ حضوراب ہمیں پنیر عنایت فرما دیجئے ہم خود ہی بانٹ لیں گی.اس پر بندر نے کہا اب تو صرف میری محنت کا بدلہ باقی رہ گیا ہے اور یہ کہہ کر اُس نے پنیر کا آخری ٹکڑہ بھی اپنے مُنہ میں ڈال لیا.یہی ان لوگوں کا حال ہے جب بھی یہ کسی قوم کا کوئی معاملہ طے کرنے لگتے ہیں یہی کہتے ہیں کہ ہمارا حق اتنا بنتا ہے اور اس حق پر بحث کرتے کرتے سارا ملک ہضم کر جاتے ہیں اور آخر میں جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ حق مانگنے والے محروم رہ جاتے ہیں اور یہ لوگ اُن کے تمام حقوق غصب کر کے اُن پر قبضہ جما لیتے ہیں.الَّذِيْنَ اِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَٞۖ۰۰۳ (ان کے لئے) جو لوگوں سے تول کر لیتے ہیں تو خوب پورا کر کے لیتے ہیں.حَلّ لُغَات.اِکْتَالُوْا:اِکْتَالُوْا اِکْتَالَ سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے.اِکْتَالَ کے دو صلے آتے ہیں مِنْ اور عَلٰی چنانچہ عربی زبان میں اِکْتَالَ مِنْہُ اور اِکْتَالَ عَلَیْہِ دونوں استعمال ہوتے ہیں اور اِکْتَالَ مِنْہُ وَعَلَیْہِ اِکْتِیَالًا کے معنے ہوتے ہیں اَخَذَ مِنْہُ وَتَوَلَّی الْکَیْلَ بِنَفْسِہٖ اس نے دوسرے سے اپنا حق وزن کر کے لیا اس خصوصیت کے ساتھ کہ پیمانہ اُس نے اپنے ہاتھ میں رکھا دوسرے کے ہاتھ میں اُسے جانے نہیں دیا.(اقرب) پس الَّذِيْنَ اِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ کے یہ معنے ہوئے کہ جب وہ لوگوں سے اپنا حق لینے کے لئے پیمانہ کے ذریعہ فیصلہ کرتے ہیں تو پیمانہ اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں اور پھر جو کچھ لیتے ہیں پورا پورا لیتے ہیں.تفسیر.یوروپین اقوام کا ہر فیصلے میں اپنا اختیار رکھنا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں عیسائی قوم کے جس نقص کو بیان فرمایا ہے اس کے اظہار کے لئے بعض اور الفاظ بھی استعمال ہو سکتے تھے.مثلاً اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ
Page 411
سکتا تھا کہ جب وہ سودا کرتے ہیں تو اپنا حق پوری طرح لے لیتے ہیں مگر اُس نے یہ نہیں کہا بلکہالَّذِيْنَ اِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ.وَ اِذَا كَالُوْهُمْ اَوْ وَّ زَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ کے الفاظ استعمال فرمائے ہیں یہ بتانے کے لئے کہ سارا معاملہ ان لوگوں کے اپنے ہاتھ میں ہو گا اور فیصلہ کا اختیار صرف اُنہی کو حاصل ہو گا خواہ انہوں نے لوگوں سے حق لینا ہویا انہوں نے لوگوں کا حق دینا ہو چنانچہ آج واقعات اس کی تصدیق کر رہے ہیں.کوئی معاملہ ہو فیصلہ کا اختیار انہی لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے.چنانچہ ہندوستان کی آزادی کا سوال ہی لے لو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہندوستانی لیڈر آپس میں بیٹھ کر کوئی فیصلہ کر سکیں.انگریز یہی کہتے ہیں کہ بیشک تم اکٹھے ہو کر غور کرو مگر تمہارا آخری کام یہ ہو گا کہ اپنے مطالبات کو ہمارے سامنے پیش کرو پھر ہمارا ختیار ہو گا کہ ہم اُن میں سے جس مطالبہ کو چاہیں منظور کریں اور جس مطالبہ کو چاہیں ردّ کر دیں.یہی بات اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمائی ہے کہ اس قوم کو دنیا پر ایسا غلبہ حاصل ہو گا کہ لوگوں کوحقوق دینے یا اُن سے اپنے حقوق لینے کا تمام اختیار انہی لوگوں کو حاصل ہو گا.دنیا میں گاہک اپنی جگہ اختیار کھتا ہے اور تاجر اپنی جگہ اختیار رکھتا ہے لیکن یہ اگر گاہک ہوں گے تب بھی کہیں گے کہ تمہیں تولنے کا اختیار نہیں.چیز تول کر ہم خود لیں گے اور اگر یہ تاجر ہوں گے تب بھی یہ کہیں گے کہ جو کچھ ہم مانگتے ہیں وہ تم دو اس سے کم ایک پائی بھی لینے کے لئے ہم تیار نہیں ہیں.غرض تمام اختیارات لینے اور دینے کے ان کو حاصل ہوں گے دوسروں کا اختیار نہیں ہو گا کہ وہ اس میں دخل دے سکیں.اس اعتراض کا جواب کہ حق کا پورا لینا تو انصاف پر دلالت کرتا ہے لیکن پھر یَسْتَوْفُوْنَ کیوں فرمایا یہاں اللہ تعالیٰ نے یَسْتَوْفُوْنَ کا لفظ استعمال فرمایا ہے جس کے معنے پورا لینے کے ہیں (اقرب)اور پورا لینا بظاہر انصاف پر دلالت کرتا ہے لیکن درحقیقت اس جگہ یَسْتَوْفُوْنَ الْحَقَّ مراد نہیں یعنی یہ مطلب نہیں کہ جتنا ان کا حق تھا وہ لیتے ہیں بلکہ یَسْتَوْفُوْنَ الْمُطَالَبَۃَ ہے یعنی جتنا مانگتے ہیں اتنا لے کر چھوڑتے ہیں اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ اس جگہ اُن کی برائی ہو رہی ہے تعریف نہیں.اور بُرائی کا پہلو یہی ہے کہ لے تو زیادہ لے اور دے تو کم دے.پس یَسْتَوْفُوْنَ سے مراد حق پورا لینا مراد نہیں بلکہ اپنا مطالبہ پورا لینا مراد ہے ہاں بطور تنزل یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ ہمیشہ حق پورا لیتے ہیں کبھی دوسرے پر رحم نہیں کرتے اور اپنے حق کا کوئی حصہ معاف نہیں کرتے یعنی روائتی شائیلاک کا سا سلوک کرتے ہیں.اس کا مزید ثبوت یہ ہے کہ اس جگہ اِکْتِیَال کا لفظ استعمال کیا ہے جس کے معنے ترازو اپنے ہاتھ میں لے کر خود تول کر لینے کے ہوتے ہیں یہ نہیں کہ کوئی دوسرا تول کر دے.ان لفظوں کے استعمال سے بھی ظاہر ہے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق اپنا حق لیتے ہیں اور دوسرے کا کوئی دخل اس میں آنے نہیں دیتے.
Page 412
یوروپین اقوام پر شائیلاک کی کہانی کا صادق آنا شائیلاک کی کہانی حقیقت میں عیسائیوں پر پوری طرح چسپاں ہوتی ہے یہ لوگ بھی جب کسی سے کچھ لینا ہوتا ہے تو ایسی سختی سے مطالبہ کرتے ہیں کہ کسی چیز کی بھی پروا نہیں کرتے لیکن جب دینے کا سوال آئے تو سو سو بہانے بنانے لگ جاتے ہیں.میں یہ بتا چکا ہوں کہ اِکْتَالَ کے دو صلے آتے ہیں.مِنْ اور عَلَی چنانچہ اِکْتَالَ مِنْہُ اور اِکْتَالَ عَلَیْہِ دونوں عربی زبان میں استعمال ہوتے ہیں اور دونوں کے ایک ہی معنے سمجھے جاتے ہیں.لیکن بعض علماء ادب نے کہا ہے کہ صلہ کے تغیّر سے اس لفظ کے مفہوم میں بھی فرق پیدا ہو جاتا ہے.وہ کہتے ہیں یہ صحیح ہے کہ اِکْتَالَ مِنْہُ اور اِکْتَالَ عَلَیْہِ دونوں صلے آتے ہیں لیکن جب اِکْتَالَ کے ساتھ عَلَی کا صلہ آئے تو اس کے معنے ہوتے ہیں اَخَذْتُ مَاعَلَیْہِ کَیْلًا کہ جو کچھ میرا اُس کے ذمہ تھا وہ میں نے اُس سے وزن کر کے لے لیا.فرّاءؔ جو مشہور نحوی ہے اُس نے یہ تشریح کی ہے اور کہا ہے کہ عَلَی کے صلہ کے ساتھ جب اِکْتَالَ کا لفظ آئے تو اس کے معنے اَخَذْتُ مَاعَلَیْہِ کَیْلًا کے ہوتے ہیں یعنی میں نے اس سے وہ چیز جو اس کے ذمہ تھی لے لی.لیکن اگر اِکْتَلْتُ مِنْہُ کہا جائے تو اس کے معنے اِسْتَوْفَیْتُ مِنْہُ کَیْلًا کے ہوتے ہیں کہ مَیں نے ماپ کر اس سے پورا پورا لےلیا یعنی زور پورا لینے پر ہوتا ہے (روح المعانی زیر آیت ھذا) گویا عَلٰی کے صلہ میں تو یہ مراد لی گئی ہے کہ جو کچھ دوسرے کے ذمہ ہو اس سے لے لیا جائے یعنی لے لینے پر زور ہوتا ہے اور مِنْ کے صلہ کے ساتھ اس لفظ کے یہ معنے ہوتے ہیں کہ ماپ کر اس سے پورا پورا لے لیا یعنی پورا پورا لینے پر زور ہوتا ہے.غرض اس آیت میں اس امر پر زور ہے کہ وہ لوگ حق لے کر اور اپنے اندازہ کے مطابق پورا لے کر چھوڑتے ہیں بات یہ ہے کہ ایک حق کالینا تو اس طرح ہوتا ہے کہ دوسرے شخص سے ہم گفتگو کرتے ہیں اُس کے دلائل سنتے ہیں اور پھر باہمی مشورہ سے فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کا اتنا حق بنتا ہے لیکن ایک زبردستی کا حق ہوتا ہے کہ دوسرے کو تحکمانہ طور پر کہا جائے کہ میرے نزدیک تمھارے ذمہ یہ حق نکلتا ہے اور اب تم سے میں اس حق کو لے کر رہوں گا.اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ یہ عیسائی لوگ ایسے ہوں گے کہ دوسروں سے کہیں جو کچھ ہم تم سے مانگتے ہیں وہ ہمیں دے دوپیمانہ اُن کے اپنے ہاتھ میں ہو گا.اپنے حق کے فیصلہ کا اختیار بھی اُن کے اپنے ہاتھ میں ہو گا اور وہ جو جی چاہے گا اپنا حق جتا کر دوسروں سے لے لیں گے اور پھر اصرار کر کے لیں گےگویا حق کی مقدار کی تعیین وہ دوسرے پر نہیں چھوڑیں گے بلکہ اس کی مقدار معین کرنے کا حق اپنے پاس رکھیں گےاور بجائے تراضیٔ فریقین سے ایک حق مقرر کرنے کے جو حق اپنے لئے خود مناسب سمجھیں گے وہ تجویز کر لیں گے مطلب یہ ہوا کہ رحم اور شفقت اُن میں بالکل نہیں ہو گی اور حق کے نام کے ماتحت ان کی کارروائیاں جبری اور ظالمانہ ہوں گی.اس تشریح کو سمجھ لینے کے بعد
Page 413
اس اعتراض کا جواب دینا آسان ہو جاتا ہے جو بعض لوگ کرتے ہیں کہ اس آیت میں ذم کا کوئی پہلو ہے ہی نہیں پھر وَیْلٌ کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا ہے وہ کہتے ہیںوَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ کہہ کر آگے یہ کہا گیا ہے کہ الَّذِيْنَ اِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ وہ مطففّف جو لوگوں سے اپنا حق پورا پورا لیتے ہیں اُن کے لئے عذاب ہے حالانکہ اپنا حق لینا محلِ ذم نہیں ہے پھر اپنا حق لینے پر اُن کے لئے وَیْل جو کلمۂ عذاب ہے کیوں استعمال کیا گیا ہے.یہ اعتراض اُن معنوں کے رو سے جو اوپر بیان کئے گئے ہیں بالکل جاتا رہتا ہے.کیونکہ حق خود مقرر کرنے پر اصرار اور پھر حق لینے میں انتہائی سختی اور عدم رحم خود محلِّ ذم ہے اور رحم اور شفقت جس قوم میں نہ ہو وہ وَیل کے نیچے ہوتی ہے.علاوہ ازیںعَلٰی کا صلہ خلاف کے معنوں میں عام طور پر استعمال ہوتا ہے پس اگر لوگوں کو ضرر اور نقصان پہنچانا اس کے مفہوم میں شامل سمجھا جائے تو یہ بھی محلِّ ذم ہے.اس صورت میں الَّذِيْنَ اِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ کے یہ معنے ہوں گے کہ وہ لوگوں سے تول کر لیتے ہیں ایسی صورت میں کہ اُن کو ضرر پہنچتا ہو.اس صورت میں بھی وَیْل کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے.اس موقعہ پر یہ اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ اگر عَلٰی بمعنے خلاف اس جگہ استعمال ہوا ہے تو پھر یَسْتَوْفُوْنَ کے کیا معنے ہوئے؟ سو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں استیفاء سے مراد استیفاء مطابق خواہش ہے نہ کہ استیفاء مطابق واقعہ.یہ نہیں کہ دوسرا اگر یہ سمجھتا ہو کہ میرے ذمہ دو سیر حق نکلتا ہے تو یہ دو سیر لے کر ہی راضی ہو جائیں گے بلکہ یہ اگر تین سیر لینا چاہیں گے تو تین سیر ہی لیں گے اس سے کم نہیں لیں گے.پس یہاں استیفاء سے مراد استیفاء مطابق واقعہ نہیں بلکہ استیفاء مطابق خواہش ہے گویا یَسْتَوْفُوْنَ کے معنے یہ ہیں یَسْتَوْفُوْنَ کَمَا یَشَآءُ وْنَ یا یَسْتَوْفُوْنَ حَسْبَ مُطَالَبَتِھِمْ اور ان معنوں میں یَسْتَوْفُوْنَ کا مفہوم عَلٰی کے مفہوم کے خلاف نہیں پڑتا بلکہ عین مطابق ہوتا ہے.بعض نے کہا ہے کہ عَلٰی اِکْتَالُوْا کا صلہ ہی نہیں بلکہ عَلٰی یَسْتَوْفُوْنَ کا صلہ ہے اور مراد یہ ہے کہ ان کا استیفاء اپنے حق میں اور دوسروں کے خلاف ہوتا ہے یعنی ایسی صورت میں استیفاء کراتے ہیں جس کا اثر دوسروں کے خلاف پڑتا ہے اور اصل جملہ یہ ہے اِذَا اكْتَالُوْا یَسْتَوْفُوْنَ عَلَى النَّاسِیعنی وہ لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہوئے اپنی خواہش کے مطابق پورا لیتے ہیں گویا اپنے حق میں تو استیفاء ہوتا ہے لیکن لوگوں کے خلاف ہوتا ہے.اکتال منہ اور اکتال علیہ میں فرق میں بتا چکا ہوں کہ لغت والوں نے لکھا ہے کہ اِکْتَالَ کا صلہ مِنْ اور عَلٰی د ونوں طرح آتا ہے اور معنوں کے لحاظ سے دونوں میں کوئی فرق نہیں لیکن مفسّرین نے اس پر بحث کی ہے کہ یہاں اِکْتَالُوْاعَلٰی کیوں آیا ہے اِکْتَالُوْا مِنْ کیوں نہیں آیا.مَیں نے اوپر ذکر کیا ہے کہ فرّاءؔ کے
Page 414
نزدیک اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں عَلٰی کاصلہ استعمال کیا ہے اور مِنْ کے صلہ کی بجائے یَسْتَوْفُوْنَ کا لفظ لے آیا ہے کیونکہ جب اِکْتَلْتُ مِنْہُ کہیں تو اس کے معنے ہوتے ہیں اِسْتَوْفَیْتُ مِنْہُ کَیْلًا.گویا اس کے نزدیک دونوں صلے استعمال ہو گئے ہیں.پس یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اِکْتَالُوْا عَلٰی کیوں آیا ہے اور اِکْتَالُوْا مِنْ کیوں نہیں آیا.یَسْتَوْفُوْنَ کا لفظ مِنْ کا قائم مقام ہے اور عَلٰی کا صلہ تو ظاہر ہی ہے.فراءؔ کی اس توجیہہ کے مطابق اعتراض کا جواب تو آ گیا لیکن یہ توجیہہ ہمیں قرآن کریم کے محاورہ کے خلاف نظر آتی ہے.قرآن کریم پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ عَلٰی ا ور مِنْ کے استعمال میں کچھ فرق ہے اور یہ درحقیقت الگ الگ معنوں میں استعمال ہوتے ہیں.قرآن کریم میں آتا ہے فَاَرْسِلْ مَعَنَاۤ اَخَانَا نَكْتَلْ وَ اِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ (یوسف:۶۴) ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دے کہ ہم تول کر لیں گے اور اس کی حفاظت بھی کریں گے.دوسری جگہ آتا ہے فَاَوْفِ لَنَا الْکَیْلَ (یوسف:۸۹) اے آقا ہمیں پورا پورا تول کر دے.جس سے ظاہر ہے کہ یوسف کے بھائیوں نے خود نہیں ماپا بلکہ دوسرے سے مپوایا.اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام خود فرماتے ہیں اَلَا تَرَوْنَ اَنِّيْۤ اُوْفِي الْكَيْلَ (یوسف:۶۰) کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں پورا پورا ماپ دیتا ہوں.ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اِکْتیال کرنے والے حضرت یوسف علیہ السلام تھے اور وہ غلّہ ماپ کر دیتے تھے بھائی ماپ نہیں کرتے تھے.مگر باوجود اس کے بھائی نَکْتَلْ کا لفظ استعمال کرتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اِکْتَالَ کا لفظ جب بھی بولا جائے تو اس کے معنے یہ ہوتے ہیں کہ اس شخص نے آپ تولا یہ غلط ہے کیونکہ قرآن کریم میں آتا ہے فَاَرْسِلْ مَعَنَا اَخَانَا نَکْتَلْ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دے کہ ہم اِکْتِیَال کریں گے مگر باوجود اس کے بھائی بھی مانتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام ہی ماپا کرتے تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام بھی کہتے ہیں کہ اَنِّيْۤ اُوْفِي الْكَيْلَ میں ماپ کر دوں گا جس سے ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ درحقیقت اِکْتَالَ مِنْہُ کا لفظ استعما ل ہو تو اس کے دونوں معنے ہوتے ہیں خواہ خود ماپ کرے یا دوسرے سے کروائے اور جب اِکْتَالَ عَلَیْہِ ہو تو صرف خود ماپ کر لینے کے معنےہوتے کیونکہ عَلٰی کا صلہ خلاف کے معنے دیتا ہے.
Page 415
وَ اِذَا كَالُوْهُمْ اَوْ وَّ زَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَؕ۰۰۴ اور جب (کسی چیز کو) اُنہیں تول کر یا وزن کر کے دیتے ہیں تو تھوڑا دیتے ہیں.حَلّ لُغَات.کَالُوْھُمْ:کَالُوْا کَالَ سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے کہتے ہیں کَالَ الطَّعَامَ وَغَیْرَہٗ وَاَکْثَرُ اِسْتِعْمَالِہٖ فِی الطَّعَامِ یعنی کَالَ کا لفظ بالعموم کھانے کی اشیاء کے ماپنے اور تولنے پر بولا جاتا ہے لیکن غیر کے لئے بھی استعمال کر لیتے ہیں نیز اس کے معنے ہیں حَقَّقَ کَمِیَّتَہٗ اَوْمِقْدَارَہٗ بِوَاسَطَۃِ اٰلَتٍ مُعَدَّۃٍ لِذَالِکَ کَالصَّاعِ وَالْاِرْدَتِ وَالذِّرَاعِ وَنَحْوَ ذَالِکَ (اقرب) کسی چیز کی کمیّت یا اُس کی مقدار اس آلہ کے ذریعہ سے جو اس کے لئے مقرر کیا گیا ہو معلوم کرنا جیسے ہمارے ہاں ایک خاص پیمانہ کو ٹوپہ کہتے ہیںاور اس کے ذریعہ ماپ کر چیزیں لیتے دیتے ہیں یا عرب میں صاع ہوا کرتاتھا اسی طرح سیروں کے ذریعہ کسی چیز کا وزن کرنا اور کہنا کہ فلاں چیز اتنے سیر ہے یا گز کے ذریعہ کسی چیز کو ماپنا.سب کے لئے کَالَ کا لفظ استعمال ہوتا ہے گویا کَالَ کے لفظ کے معنے یہ ہیں کہ اندازہ کے لئے جو چیز مناسب حال مقرر ہو اُس سے کوئی چیز لینا.اگر وزن کی چیز ہے تو باٹوں کے ذریعہ وزن کر کے لینا.اگر پیمانہ کے ذریعہ ماپنے والی چیز ہے تو پیمانہ سے ماپ کر لینا اور اگر گز سے اس کا اندازہ ہو سکتا ہو تو گز سے اندازہ کر کے لینا.پس کَالَ میں تینوں چیزیں شامل ہیں صاعؔسے ماپنا.باٹوںؔ سے وزن کرنا اور گزؔ وغیرہ سے اندازہ کرنا.مگر چونکہ قرآن کریم نے کَالُوْھُمْ کے بعد اَوْوَّزَنُوْھُمْ کے الفاظ بھی استعمال فرمائے ہیں اس لئے ہمیں وزن کو الگ رکھنا پڑے گا اور کَالُوْھُمْ میں صرف صاع کے ذریعہ یا گز کے ذریعہ جو اندازہ لگایا جاتا ہے اسی کو شامل سمجھنا پڑے گا.اگر قرآن کریم اَوْوَّزَنُوْھُمْ کے الفاظ زائد نہ کرتا تو کَالُوْھُمْ میں وزن بھی شامل ہوتا.جیسا کہ لُغت والوں نے وزن کو بھی اس میں شامل کیا ہے مگر چونکہ وزن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے الگ کر دیا ہے اس لئے کَالُوْھُمْ میں صرف دوچیزیںرہ جائیں گی.صاع کے ذریعہ ماپنا یا ذراع کے ذریعہ ماپنا.اسی طرح لُغت والے لکھتے ہیں وَقَدْیَتَعَدّٰی اِلٰی مَفْعُوْلَیْنِ فَیُقَالُ کِلْتُ لِزَیْدِنِ الطَّعَامَ (اقرب) یعنی کبھی اس کے دو مفعول بھی آجاتے ہیں جیسے کہتے ہیں میں نے زید کو غلّہ اندازہ کر کے دیا.اور کبھی مفعولِ اوّل پر لام بھی آجاتا ہے چنانچہ کہتے ہیں کِلْتُ لِزَیْدِنِ الطَّعَامَ یہ لفظ وزن کے لئے بھی استعمال ہو جاتا ہے جیسے کہتے ہیں کَالَ الصَّیْرَفُ الدَّرَاھِمَ اَیْ وَزَنَھَا (اقرب) صرّاف نے درہم تول کر دئے.پھر کَالَ کا لفظ اس سے بھی وسیع معنوں میں استعمال ہو جاتا ہے کہتے ہیں کَالَ الشَّیْءَ بِالشَّیْءِ: قَاسَہٗ کسی چیز کو کسی چیز پر قیاس کیا.نیز کہتے ہیں کِلْتُ فُلَانًا بِفُلَانٍ اَیْ قِسْتُہُ
Page 416
بِہٖ یعنی میں نے اس شخص پر فلاں شخص کا اندازہ اور قیاس کیا اور کہتے ہیں کَالَ الْفَرَسُ بِغَیْرِہٖ: قَاسَہٗ بِہٖ فِی الْـجَرْیِ (اقرب) یعنی گھوڑا دیکھا.اس کی دَوڑ دیکھی اَور پھرقیاس کِیا کہ فلاں گھوڑا زیادہ اچھا ہے کیونکہ اس کی دوڑ اچھی ہے اور فلاں گھوڑا کمزور ہے کیونکہ اس کی دوڑ خراب ہے، گویا ظاہری ماپ تول کے علاوہ باطنی اندازہ بھی اس سے استعارۃً مراد لے سکتے ہیں.تفسیر.میسحی اقوام کا وزن اور کیل میں غیر اقوام کو لوٹنا اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بیان فرماتا ہے کہ جب یہ کسی قوم کو ماپ کر دیتے ہیں یا اسے وزن کر کے دیتے ہیں تو اس میں ہمیشہ دوسرے کو نقصان پہنچاتے ہیں.یعنی ظاہری شکل ماپ اور تول کی ہو گی اور وہ دوسرے کو یہی دکھائیں گے کہ ہم تمہیں جو کچھ دے رہے ہیں.ماپ تول کر دے رہے ہیں اور اندازہ کے مطابق بالکل صحیح صحیح دے رہے ہیں.نتیجہ یہ ہو گا کہ دوسروں کو نقصان ہو گا اور اِن کو فائدہ ہو گا.یہ خرابی ایسی ہے جو خصوصیت کے ساتھ مسیحیوں میں پائی جاتی ہے.چنانچہ وزن کو لیں تب بھی یہ قوم دوسروں کو لوٹتی ہے اور کَیل کو لیں تب بھی یہ قوم دوسروں کو لوٹتی ہے اس قوم کو بڑا غلبہ تجارت سے حاصل ہوا ہےاور تجارت میں یہ لوگ حد درجہ کی چالاکی اور ہوشیاری سے کام لیتے ہیں.جہاں تک انفرادی تجارت کا سوال ہے یوروپین لوگوں میں سے سو میں سے ایک بھی دھوکا نہیں کرے گا بلکہ ہزار میں سے ایک بھی دھوکا نہیں کرے گا.اس کے مقابلہ میں ایشائی لوگوں کی یہ حالت ہے کہ سو میں سے ننانوے دھوکا کریں گے بلکہ ننانوے کیا سو میں سے سو ہی دھوکاباز ہوں گے.ہزار میں سے ایک شاید کوئی ایسا نکل آئے جو انفرادی تجارت میں دھوکا بازی نہ کرے لیکن بالعموم ایشائی اس پہلو میں نہایت بُرا نمونہ دکھاتے ہیں.اگر چیز کو تولتے ہوئے وہ تھوڑی سی بے ایمانی نہ کر لیں اور دوسرے کو کسی قدر کم چیز نہ دیں تو ان کا دل دھڑکنے لگ جاتا ہے اور وہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح ڈنڈی مار کر ہم کچھ فائدہ اٹھا لیں.پس جہاں تک انفرادی تجارت کا سوال ہے یوروپین لوگوں کا نمونہ اس بارہ میں نہایت اعلیٰ ہے مگر جب قومی تجارت کا سوال آ جائے تو یہ قوم اتنی لوٹ کرتی ہے کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں ایسے کئی واقعات ہیں کہ انہوں نے کروڑوں کروڑ روپیہ کا سامان اور توپیں وغیرہ غیر ملکوں کو بنا کر دئے.مگر نہ وہ توپیں اچھی تھیں نہ وہ جہاز اچھے تھے نہ وہ سامان اچھا تھا.بالکل ردّی اور گندہ سامان انہوں نے بھجوا دیا اور کروڑوں کروڑروپیہ وصول کر لیا.بے شک خوردہ فروشی میں ان کی دیا نت سےکوئی لگّا نہیں کھا سکتا.لیکن جہاں بڑی تجارت کا سوال آ جائے وہاں اس قدر لُوٹ مچاتے ہیں کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں.ملکوں کے ملک غارت کر جاتے ہیں اور تجارت میں پالیٹکس کو شامل کر دیتے ہیں.پس
Page 417
درحقیقت وہ تجارت نہیں ہوتی بلکہ ایک رنگ کی سیاست ہوتی ہے جس کے ذریعہ یہ دوسرے ملک پر غلبہ حاصل کر لیتے ہیں.فرض کرو الف اور باء دو یوروپین قومیں ہیں اور ان کی آپس میں دشمنی ہے الف سمجھتا ہے کہ اگر میری باء سے لڑائی ہو گئی تو ج اس لڑائی میںضرور باء کی طرف سے شامل ہو گا لیکن اسے سامان جنگ کے لئے ہماری امداد کی ضرورت ہے جب ایسی صورت پیدا ہو تو الف.ج کے لئے سامانِ جنگ کے ریٹ گرا دے گا اور اس کے لئے سامان جنگ تیار کرنے پر آمادگی ظاہر کرے گا مگر کوئی چیز وقت پر تیار کر کے نہیں دے گا.یہاں تک کہ لڑائی کا وقت آجائے گا اور ج سامان نہ ہونے کی وجہ سے یا باء کی مدد نہ کر سکے گا یا دشمن کے ہاتھوں پیسا جائے گا.تو جہاں تک بڑی تجارتوں کا سوال ہے یا قومی تجارتوں کا سوال ہے یہ قوم خطرناک تطفیف کرتی ہے.اور اس سورۃ میں ان کی اسی خرابی کا ذکر کیا گیا ہے.کیل کے ساتھ لفظ وزن کا اضافہ کرنے کی وجہ یہاں ایک سوال اور بھی پیدا ہوتا ہے جس کا جواب دینا ضروری ہے.وہ سوال یہ ہے کہ پہلے فرمایا تھا الَّذِيْنَ اِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ مگرا س کے بعد وَاِذَا کَالُوْھُمْ اَوْوَّزَنُوْھُمْ یُخْسِرُوْنَ فرمایا ہے.یعنی کَیل کے ساتھ وزن کے لفظ کا اضافہ کر دیا ہے.حالانکہ جیسا کہ حل لغات میں بتایا جا چکا ہے کَیْل کے لفظ میں ماپ تول وغیرہ سب شامل ہے.اگر تو کَیْل کے وہی معنے لئے جائیں جو لغت میں آتے ہیں تو اس صورت میں کَالُوْھُمْ کے بعد اَوْوَّزَنُوْھُمْ کے لفظ کی زیادتی کی کوئی ضرورت نہ تھی کیونکہ کَیل کے معنوں میں ہی وزن کے معنے شامل ہیں.اور اگر یہ توجیہ کی جائے کہ اس جگہ اللہ تعالیٰ نے کَالَ کے زیادہ معروف معنوں کو لیا ہے جو ماپنے کے ہیں تو پھر یہ اعتراض پڑتا ہے کہ اس صورت میں پہلی آیت میں بھی وزن کا لفظ بڑھانا چاہیے تھا مگر وہاں یہ لفظ نہیں رکھا گیا.خلاصہ یہ کہ یا تو پہلی آیت میں یوں کہا جاتا اَلَّذِیْنَ اِذَااکْتَالُوْا وَاتَّزَنُوْاعَلَی النَّاسِ یَسْتَوْفُوْنَ یا پھر دوسری آیت یوں ہوتی کہ وَاِذَا کَالُوْھُمْ یُخْسِرُوْنَ.زجاج نے یہ سوال اٹھا کر اتنا جواب دیا ہے کہ چونکہ کَیل اور وزنؔ معنوں میں مقاربت اور مشارکت رکھتے ہیں اس لئے ایک کو بیان کر کے دوسرے کو چھوڑ دیا گیا ہے کیونکہ ذہن خود اس کا اندازہ کر لیتا ہے پس پہلی آیت سے بھی مراد یہ ہے کہ اِکْتَالُوْا وَاتَّزَنُوْا گویا دو قریب المعنٰی الفاظ میں صرف ایک پر حصر کر لیا گیا ہے.یہ جواب ایک حد تک درست ہے اور قرآن کریم میں اس قسم کی اَور بھی مَثالیں پائی جاتی ہیں کہ جہاں دو الفاظ اپنے معنوں کے لحاظ سے ایک دوسرے سے قرابت اور اتصال رکھتے ہوں وہاں ایک کو بیان کر دیا جاتا ہے اور دوسرے کا ذِکر چھوڑ
Page 418
دیا جاتا ہے مثلا ًگرمی سردی کا اکٹھا ذکر کرنا ہو تو خالی گرمی یا خالی سردی کا ذکر کر دیا جائے گا.یا سورج چاند کا اکٹھا ذکر کرنا ہو تو صرف سورج کا ذکر کر دیا جائے گا اور چاند کا ذکر اسی میں شامل سمجھ لیا جائے گا.مفسرین کی اس بات پر بحث کہ کَالُوْھُمْ اَوْ وَزَنُوْھُمْ میں کیل کے ساتھ وزن کے لفظ کا کیوں اضافہ کیا گیاہے پس یہ صحیح ہے کہ دو قرابت رکھنے والے الفاظ میں سے بعض دفعہ ایک کو چھوڑ کر دوسرے پر حصرکر لیا جاتا ہے لیکن اس جواب سے تسلی نہیں ہوتی.کیونکہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر دوسری آیت میں کَالُوْھُمْ کے ساتھ اَوْوَّزَنُوْھُمْ کیوں بڑھایا گیا وہاں بھی کَیل کے ذکر پر ہی کفایت کی جاتی اور وزنؔ کا ذکر ساتھ نہ کیا جاتا.اس کا جواب یہ ہے کہ کَیل میں نقصان کا خطرہ بہت کم ہوتا ہے لیکن وزن میں نقصان کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے.ہمارے ملک میں چیزیں ماپنے کے لئے ٹوپہ ہوتا ہے یا بعض لوگوں نے آدھ آدھ سیر یا پائو پائو وزن کے گلاس رکھے ہوئے ہوتے ہیں یا بعض گڈویاں ایسی ہوتی ہیں جن میں معیّن اندازہ کی چیز آجاتی ہے.ایسے اندازہ کے جو برتن ہوتے ہیں خواہ ٹوپہ ہو یا گلاس یا گڈویاں ہوں ان میںکمی صرف ایسی ہی ہوسکتی ہے جو نظری ہو.یہ نہیں ہو سکتا کہ سیر میں سے پائو کم ہو جائے.اِتنا تو ہو سکتا ہے کہ ماپتے وقت ذرا سے کنارے نیچے رہ جائیں مگر اس سے زیادہ کمی نہیں آسکتی لیکن وزن میں بڑی بھاری کمی کی جا سکتی ہے اور ڈنڈی مارنے کا فن ایسا ہے کہ سیر کی جگہ بعض دفعہ تین تین پائو چیز رہ جاتی ہے اور لینے والے کو بھی معلوم بھی نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ دھوکا کیا جا رہا ہے لیکن صاع میں یا ٹوپہ میں یا پڑوپی میں سیر میں پائو کا فرق کبھی نہیں پڑے گا پس چونکہ وزن میں بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے اس لئے جہاں لینے کا سوال تھا وہاں صرف اِکْتَالَ کا لفظ استعمال کر دیا اور بتا دیا کہ جب وہ ما پ کے ذریعہ لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں اس میں آپ ہی یہ مضمون بھی آ گیا کہ جو لوگ تھوڑا نقصان برداشت نہیں کر سکتے وہ بڑا نقصان کب برداشت کر سکتے ہیں.پس اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمایا الَّذِيْنَ اِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ کہ وہ لوگ ایسے ہیں کہ جب لوگوں سے ماپ کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں تو اس سے آپ ہی یہ نتیجہ نکل آیا کہ جو لوگ کم نقصان بھی جو ماپ سے تعلق رکھتا ہے برداشت نہیں کر سکتے وہ بڑا نقصان تو کسی حالت میں بھی برداشت نہیں کر سکتے.مگر اِکْتَال کے بالمقابل جب کَالُوْھُمْ کہا تو تھوڑا دینے کے لفظ سے یہ ثابت نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ زیادہ بھی لوٹ لیتے ہیں کیونکہ اگر کوئی شخص چھوٹا نقصان پہنچائے تو اس سے یہ ثابت نہیں ہو جاتا کہ وہ بڑا نقصان بھی پہنچا سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص چھوٹا گناہ کر لے مگر جب بڑا گناہ آئے تو اس سے ڈر جائے پس چونکہ کَالُوْا کا لفظ اصل حقیقت پر پوری طرح روشنی نہیں ڈالتا تھا اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ہی اَوْوَّزَنُوْھُمْ کا لفظ استعمال کر کے بتا دیا کہ جہاں تھوڑا
Page 419
نقصان پہنچا سکیں وہاں تھوڑا نقصان پہنچاتے ہیں اور جہاں بس چلے وہاں زیادہ نقصان پہنچا دیتے ہیں.پس الَّذِيْنَ اِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ.وَاِذَا کَالُوْھُمْ اَوْوَّزَنُوْھُمْ یُخْسِرُوْنَ کے معنے یہ ہوئے کہ جب انہوں نے لوگوں سے اپنا کوئی حق لینا ہوتا ہے تو چھوٹا نقصان نہیں اٹھاتے لیکن جب دینے کا سوال آئے تو اگر چھوٹا نقصان پہنچا سکیں تو چھوٹا نقصان پہنچا دیتے ہیں اور اگر بڑا نقصان پہنچا سکیں تو بڑا نقصان پہنچا دیتے ہیں.پس ان معانی کی جو فطرتی ترتیب ہے اُس کے لحاظ سے اِکْتَالُوْا کے بعد اِتَّزَنُوْا کا حذف مطابق بلاغت تھا لیکن کَالُوْھُمْ کے بعد وَزَنُوْا کا لفظ حذف کرناخلاف اصولِ بلاغت تھا.اَلَا يَظُنُّ اُولٰٓىِٕكَ اَنَّهُمْ مَّبْعُوْثُوْنَۙ۰۰۵لِيَوْمٍ عَظِيْمٍۙ۰۰۶ کیا یہ (لوگ) یقین نہیں کرتے کہ وہ اٹھائے جائیں گے اس عظیم الشان وقت (کا فیصلہ دیکھنے) کے لئے تفسیر.فرماتا ہے اب تو یہ قومیں ایک دائرہ میں بیٹھی ہوئی ہیں اور یوں سمجھتی ہیں کہ دُنیا کی کوئی طاقت اُن کا کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتی.لیکن ایک دن آئے گا جب ایک دوسری قسم کا بعث ہو گا.لِیَوْمٍ عَظِیْمٍ سے مراد.لِیَوْمٍ عَظِیْمٍ سے قیامت بھی مراد ہو سکتی ہے اور وہ دن بھی اس سے مراد ہو سکتا ہے جب موجودہ دَور کا نتیجہ نکلے گا.درحقیقت ہر قوم کا الگ الگ دَور ہوتا ہے اور ہر دَور کی الگ الگ قیامت ہوتی ہے بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ لِیَوْمٍ عَظِیْمٍ سے مراد لِـحِسَابِ یَوْمٍ عَظِیْمٍ ہے یعنی یوم عظیم کے حساب کے لئے.يَّوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَؕ۰۰۷ جس وقت (تمام) لوگ سب جہانوں کے رب (کا فیصلہ سننے) کے لئے کھڑے ہوں گے.تفسیر.دنیا کی کوئی قوم ایسی نہیں جس نے ترقی کی ہو اور پھر اس پر ایک محاسبہ کا دن نہ آیا ہو مگر عجیب بات یہ ہے کہ جس طرح افراد کو اپنی موت بھولی ہوئی ہوتی ہے اسی طرح اقوام اپنی موت کے دن سے غافل اور بے پرواہ ہوتی ہیں دنیا میں سب سے زیادہ یقینی اور قطعی چیز اگر کوئی ہے تو وہ موت ہے مگر موت ہی انسان کو سب سے زیادہ بھولی ہوئی ہوتی ہے ہر شخص جانتا ہے کہ اُس کا باپ مرا.اُس کا دادا مرا.اُس کا پڑدادا مرا ہر شخص جانتا ہے کہ اُس کا فلاں فلاں رشتہ دارمر چکا ہے اور جو باقی ہیں وہ بھی ایک دن مر جائیں گے مگر پھر سب سے زیادہ اگر کسی چیز سے وہ
Page 420
غافل ہوتا ہے تو وہ موت ہی ہے.اسی طرح یہ عجیب بات ہے کہ دنیا کی ہر قوم مر چکی ہے اور جو قومیں آج موجود ہیں وہ بھی ایک دن مر جائیں گی مگر قومیں سب سے زیادہ اس موت سے غافل رہتی ہیں.قرآن کریم نے اس امر پر بڑا زور دیا ہے اور بار بار فرمایا ہے کہ بتائو کہ کیا کوئی قوم ایسی بھی ہے جو موت سے بچی ہو.تاریخی لحاظ سے اگر تحقیق کی جائے تو ایک ہزار سے کم اُن اقوام کی تعداد نہیںنکلے گی جنہوں نے اپنے اپنےزمانہ میں دنیا پر اس قدر غلبہ پایا کہ لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ ان قوموں نے میدان کو جیت لیا ہے اور اُن فاتح اقوام نے بھی اپنے غرور میں یہ خیال کرنا شروع کر دیا کہ گز شتہ قومیں تومر گئیں.عروج کے بعد زوال سے ہمکنا ر ہو گئیں.عزت کے بعد ذلّت کے گڑھے میں گر گئیں مگر ہم اس ترقی کے بعد مر نہیں سکتیں مگر آخر وہ وقت آیا جب وہ فاتح اقوام بھی مٹ گئیں وہ بھی تباہ اور برباد ہو گئیں اور اُن کا نام بھی دنیا سے ناپید ہو گیا.مسیحی اقوام کا اپنی موت سے غافل ہونا پس فرماتا ہے یہ مغربی اقوام جنہوں نے ظلم پر اپنی کمر باندھی ہوئی ہے جو دنیا پر آفت ڈھا رہے ہیں اور جو لوگوں کے حقوق کو دباتے چلے جا رہے ہیں اَلَا يَظُنُّ اُولٰٓىِٕكَ اَنَّهُمْ مَّبْعُوْثُوْنَ.لِيَوْمٍ عَظِيْمٍ.کیا اُن کو کبھی خیال نہیں آتا کہ ہمارا ایک اور بعث بھی ہونے والا ہے اُس بڑے دن کے لئے جس دن وُہ رب العالمین خدا کے سامنے پیش ہوں گے اور خُدا اُن سے کہے گا کہ کیا ایشیائی میر ے بندے نہیں تھے.کیا افریقن میرے بندے نہیں تھے.پھر تم نے کیا کِیا کہ اُن سے ظالمانہ سلوک روا رکھا؟ جب یہ یوم البعث آئے گا تو رب العالمین خدا ان کو نیچے کر دے گا اور جو نیچے ہوں گے اُن کو اوپر کر دے گا اسی کی طرف بُعْثِرَ مَا فِی الْقُبُوْرِ(العٰدیٰت:۱۰) میں اشارہ کیا گیا ہے.بَعْثَرَ کے معنے ہوتے ہیں زمین کو اُلٹ دینا اُوپر کی چیز کو نیچے اور نیچے کی چیز کو اوپر کر دینا.اللہ تعالیٰ بھی اُس دن ایسا ہی کرے گا کہ ان حاکم اقوام کو تختِ حکومت سے محروم کر دے گا.اور اُن لوگوں کو جنہیں یہ ذلیل قرار دیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ حکومت کے تخت پر بٹھا دے گا.غالب اقوام کا مغلوب ہوجانا درحقیقت قوموں کی ترقی اور اُن کا تنزل ایک دَوری کیفیت رکھتا ہے.جس طرح بچے آپس میں کُشتی کرتے ہیں تو ایک بچہ دوسرے کو گرا کر اُس کے سینہ پر چڑھ جاتا ہے.ماں باپ یہ نظّارہ دیکھتے رہتے ہیں آخر جب دیکھتے ہیں کہ اُوپر والا اُترتا نہیں تو اُس کی ٹانگ گھسیٹ کر کھینچ لیتے ہیں اور پھر دوسرا بچہ اس کے سینہ پر چڑھ جاتا ہے.یہی حال قوموں کا ہے اللہ تعالیٰ جب دیکھتا ہے کہ ایک قوم اپنےغلبہ سے ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہے تو اُسے گھسیٹ کر حکومت کے تخت سے اُتار لیتا ہے اور محکوم قوموں کے ہاتھ میں بادشاہت کی باگ دوڑ دے دیتا ہے.دُنیا میں قوموں کے بڑے بڑے لمبے غلبے ہوئے ہیں.عیسائیت کا غلبہ تو صرف تین سو سال ہے.
Page 421
مسلمانوں کا ہزار سال تک غلبہ رہا مگر وہ بھی مٹ گیا.پس فرماتا ہے کیا ان کے دلوں میں یہ کبھی خیال نہیں آتا کہ ہمارا بھی ایک بعث ہو گا.ہم پر بھی وہ دن آنے والا ہے جو ہمارے محاسبہ کا دن ہو گا بعث ؔ کا لفظ اس لئے استعمال کیا گیا ہے کہ نتیجہ کے دن صرف قوم کے موجودافراد کے اعمال کا ہی نتیجہ نہیں نکلتا بلکہ اُن کے آباء کے اعمال کا نتیجہ بھی نکلتا ہے جب ایک قوم دوسری قوم کے خلاف اُٹھتی ہے تو صرف زندہ لوگوں کے اعمال کا محاسبہ نہیں لیتی بلکہ اُن کے آباء کے سلوک کا بدلہ بھی لیتی ہے.اس طرح گویا قوم کے سب افراد زندہ ہو کر اپنا حساب پیش کرتے ہیں.يَّوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ میں درحقیقت يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْـًٔا کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ اب تو یہ مشرقی اور مغربی.گورے اور کالے.یوروپین اور ایشیائی میں فرق کرتے ہیں مگر ایک دن آئے گاجب یہ لوگ اُس خدا کے سامنے کھڑے کئے جائیں گے جو رب العالمین ہے.وہ اس وقت ان لوگوں سے ان مظالم کے بارہ میں باز پُرس کرے گا اور کہے گا کہ کیوں تم نے ایک طبقہ کو ذلیل کیا.اور کیوں اُس کو محکوم و مغلوب رکھا.آخر خدا کسی ایک قوم کا نہیں بلکہ وہ رب العالمین ہے.وہ ایشیائیوںؔ کا بھی خدا ہے اور افریقنوں ؔ کا بھی خدا ہے اور چینیوں ؔکا بھی خدا ہے اور جاپانیوںؔ کا بھی خدا ہے اور انگریزوںؔ کا بھی خدا ہے اور امریکنوں کا بھی خدا ہے.وہ اپنے بندوں کو اُسی کے ماتحت دیکھ کر خوش ہو سکتا ہے جو رب العالمین کی صفت اپنے اندر لے لے اور اُس کی ربوبیت کا کامل مظہر بن جائے.عارضی حکومتیں دنیا میں بے شک ہوتی چلی آئی ہیں اور وہ تھوڑے تھوڑے عرصہ کے بعد مٹتی بھی رہی ہیں.لیکن مستقل طور پر وہی قوم دنیا پر حکومت کر سکتی ہے جو لوگوں سے زائد حقوق نہ مانگے.اور اُن سے کہے کہ یہ ہماری نہیں بلکہ تمہاری حکومت ہے.جو قوم دُنیا میں بنی نوع انسان کی خدمت کا احساس لے کر کھڑی ہو گی اور پھر زائد حقوق مانگنے کے لئے بھی تیار نہیں ہو گی وہ ہمیشہ رہے گی.اُس کے خلاف لوگوں کو بغاوت کرنے کی کبھی ضرورت ہی پیش نہیں آسکتی.خدا تعالیٰ کے حساب لینے سے مراد خدا تعالیٰ کے حساب لینے کے یہ معنے نہیں کہ وہ خود براہ راست حساب لے.قیامت کے دن وہ خود حساب لے گا اور اس دنیا میں وہ انسانوں میں سے ہی کسی فرد یا قوم کو حساب لینے کے لئے کھڑا کر دیتا ہے اس قوم کا حساب لینا خدا تعالیٰ کا حساب لینا ہی کہلاتا ہے.
Page 422
کَلَّاۤ اِنَّ كِتٰبَ الْفُجَّارِ لَفِيْ سِجِّيْنٍؕ۰۰۸وَ مَاۤ اَدْرٰىكَ مَا ایسا نہیں (جو یہ سمجھتے ہیں) بدکاروں (کی جزا) کا حکم یقیناً سِجّین میں ہے اور تجھے کس نے بتایا ہے کہ سجین کیا ہے.سِجِّيْنٌؕ۰۰۹كِتٰبٌ مَّرْقُوْمٌؕ۰۰۱۰ وہ ایسا حکم ہے جس (کے اٹل ہونے) پر مُہر لگائی گئی ہے.حَلّ لُغَات.سِجِّیْنٌ سِجِّیْنٌکے لغت میں دو معنے لکھے ہیں (۱)اَلدَائِمُ (۲)اَلشَّدِیْدُ (اقرب) یعنی سجِّین کے لفظ کے معانی عربی زبان میں دائم اور شدید کے ہوتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں اس لفظ کے کوئی بھی معنے نہیں ہیںکیونکہ یہ عربی لفظ نہیں ہے.وہ کہتے ہیں اصل میں سجّین کا نون.لام سے بدلہ ہوا ہے اور یہ لفظ سجل سے نکلا ہے.جیسا کہ قرآن کریم میں ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ (الانبیاء:۱۰۵) اس صورت میں اس کے معنے تحریر کرنے کے ہیں اور یاپھر یہ لفظ سِجِّیْل بمعنی اَن گھڑے پتھر کے ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے.تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ (الفیل:۵) لیکن یہ استدلال درست نہیں اس لئے کہ سجّین کے معانے فراءؔ اور زجاجؔ اور ابوعبیدہؔ نے کئے ہیں اور یہ لوگ علم ادب میں بہت بلند مرتبہ رکھنے والے تھے یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک لفظ عربی زبان کا تونہ ہو اور وہ اس کے معنے کرنے لگ جاتے.اپنے معنوں کی تائید میں انہوں نے بعض اشعار بھی نقل کئے ہیں (روح المعانی )جن میں سجِّین کا لفظ پُرانے شعراء نے استعمال کیا ہے پھر جب ہم ذاتی طور پر غور کرتے ہیں تو ہمیں عربی زبان میں اس لفظ کے اَور مادے بھی مل جاتے ہیںمثلاً سَجَنَہٗ سَجْنًا کے معنے ہوتے ہیں حَبَسَہٗ فِیْ سِجْنٍ اس کو قید خانہ میں بند کر دیا.اور سَجَنَ الْھَمَّ کے معنی ہوتے ہیں اَضْمَرَہٗ اس نے اپنے غم کو چھپا لیا.(اقرب) پس جب کہ اس لفظ کے دوسرے مادے عربی زبان میں استعمال ہوتے ہیں اور جب کہ عربی زبان کے ماہرین نے اس کے معنے دائم اور شدید کے کئے ہیں تو یہ خیال کر لینا کہ یہ لفظ عربی زبان کا نہیں بلکہ کسی اَور زبان کا ہے جسے عربی زبان میں شامل کر لیا گیا ہے قطعًا غلط اور بے بنیاد بات ہے.درحقیقت یہ ایک غلطی ہے جو بعض عرب مفسّروں کو لگی ہے.جب وہ ایک لفظ کو جو عام طور پر عربی میں استعمال نہیں ہوتا دیکھتے ہیں تو فوراً یہ خیال کر لیتے ہیں کہ یہ عربی کا لفظ نہیں حالانکہ دوسرے ماہرین لغت اسے عربی کا لفظ قرار دیتے ہیں.ان کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھا کر آج کل کے عیسائی ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ اعتراض کرتے
Page 423
رہتے ہیں کہ قرآن کریم میںغیر زبانوں کے الفاظ پائے جاتے ہیں اور غیر زبانوں کے الفاظ کی وجہ سے وہ نتیجہ یہ نکالتے ہیں کہ قرآن کریم کے متعلق جو یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ وہ عَرَبِیٌّ مُّبِیْنٌ میں نازل کیا گیا ہے یہ غلط ہے حالانکہ اگر ان مفسرین کی بات کو جو کہتے ہیں کہ قرآن کریم کا فلاں فلاں لفظ عربی نہیں تسلیم بھی کر لیا جائے تو بھی یہ اعتراض عقل کے بالکل خلاف ہے.دنیا کی کوئی زبان ایسی نہیں جس میں غیر زبان کا کوئی لفظ نہ پایا جاتا ہو.دو چار فقرے کہہ لینا اَور بات ہے، مگر متمدن زمانہ کی کوئی بڑی تحریر ایسی نہیں ہو سکتی جس میں غیر زبان کا کوئی لفظ نہ آئے.بائبل میں بھی غیر زبانوں کے الفاظ موجود ہیں.ویدوں پر بھی یہ اعتراض عائد ہوتا ہے کہ اس میں غیر زبانوں کے الفاظ استعمال کئے گئے ہیں.صرف ایک شخص ایسا گزرا ہے جس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں اپنی کتاب میں غیر زبان کے الفاظ استعمال نہیں کروں گا.اور اس نے اپنے دعویٰ کو صحیح ثابت کرنے کے لئے بڑا زور لگایا وہ بڑا بھاری ادیب تھا اور بڑا مشہور عالم تھا.مگر وہ بھی اس دعویٰ میں پورا نہیں اترا اور اِسے بیسیوں غیر زبان کے الفاظ اپنی کتاب میںاستعمال کرنے پڑے.میری مراد فردوسیؔ سے ہے اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ مَیں پہلوی زبان میں شاہنامہ لکھوں گا.مگر شاہنامہؔ میں بیسیوں الفاظ غیر زبانوں کے پائے جاتے ہیں.بعض عربی کے ہیں بعض تازہ فارسی کے ہیں اور بعض دوسری زبانوں کے ہیں.مختلف زبانوں میں غیر زبانوں کے الفاظ درحقیقت کوئی متمدن زبان ہو ہی نہیں سکتی جس میں آپس کے میل جول کی وجہ سے دوسری ز بانوں کے الفاظ داخل نہ ہو جائیں اور بعض دفعہ تو چسکا پیدا ہو جاتا ہے کہ فلاں زبان کا یہ لفظ ہم اپنی ز بان میں ضرور شامل کر لیں اور اس طرح رفتہ رفتہ وہ لفظ زبان میں شامل کر لیا جاتا ہے.مثلاً انگریزی زبان میں پکّاؔ کا لفظ عام طور پر استعمال ہوتا ہے حالانکہ یہ اُردو زبان کا لفظ ہے مگر آپس کے میل جول کی وجہ سے یہ لفظ انگریزوں کو ایسا پسند آیا کہ انہوں نے اسے اپنی زبان میں شامل کر لیا یہاں تک کہ انگریزی لغت کی کتابوں میں بھی پکا کا لفظ درج ہوتا ہے اور اس کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہوتا ہے کہ یہ اردو زبان کا لفظ ہے جو انگریزی زبان میں آگیا ہے.اسی طرح بکواسؔ کا لفظ ہے جو انگریزوں کو پسند آگیا.چنانچہ بہت سے انگریز جب دوسرے پر ناراض ہوتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں do not buckیعنی بکواس مت کرو.یہ بک کا لفظ بھی اردو سے ہی انگریزی میں منتقل ہوا ہے.اِسی طرح اور سینکڑوں الفاظ ہیں جو عربی یا اردو سے لے کر انگریزی زبان میں شامل کر لئے گئے ہیں مثلاًایڈمرل ADMIRAL کا لفظ انگریزی میں استعمال ہوتا ہے جو امیر البحر سے بگڑا ہوا ہے ایڈمرل امیر البحر کو کہا جاتا ہے انگریزوں نے الامیر کا لفظ رہنے دیا اور بحر کو چھوڑ دیا.تو یہ ایک حقیقت ہے کہ ہر زبان کے الفاظ دوسری
Page 424
مختلف زبانوں میں غیر زبانوں کے الفاظ درحقیقت کوئی متمدن زبان ہو ہی نہیں سکتی جس میں آپس کے میل جول کی وجہ سے دوسری ز بانوں کے الفاظ داخل نہ ہو جائیں اور بعض دفعہ تو چسکا پیدا ہو جاتا ہے کہ فلاں زبان کا یہ لفظ ہم اپنی ز بان میں ضرور شامل کر لیں اور اس طرح رفتہ رفتہ وہ لفظ زبان میں شامل کر لیا جاتا ہے.مثلاً انگریزی زبان میں پکّاؔ کا لفظ عام طور پر استعمال ہوتا ہے حالانکہ یہ اُردو زبان کا لفظ ہے مگر آپس کے میل جول کی وجہ سے یہ لفظ انگریزوں کو ایسا پسند آیا کہ انہوں نے اسے اپنی زبان میں شامل کر لیا یہاں تک کہ انگریزی لغت کی کتابوں میں بھی پکا کا لفظ درج ہوتا ہے اور اس کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہوتا ہے کہ یہ اردو زبان کا لفظ ہے جو انگریزی زبان میں آگیا ہے.اسی طرح بکواسؔ کا لفظ ہے جو انگریزوں کو پسند آگیا.چنانچہ بہت سے انگریز جب دوسرے پر ناراض ہوتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں do not buckیعنی بکواس مت کرو.یہ بک کا لفظ بھی اردو سے ہی انگریزی میں منتقل ہوا ہے.اِسی طرح اور سینکڑوں الفاظ ہیں جو عربی یا اردو سے لے کر انگریزی زبان میں شامل کر لئے گئے ہیں مثلاًایڈمرل ADMIRAL کا لفظ انگریزی میں استعمال ہوتا ہے جو امیر البحر سے بگڑا ہوا ہے ایڈمرل امیر البحر کو کہا جاتا ہے انگریزوں نے الامیر کا لفظ رہنے دیا اور بحر کو چھوڑ دیا.تو یہ ایک حقیقت ہے کہ ہر زبان کے الفاظ دوسری زبانوں میں استعمال ہوتے رہتے ہیں مگراس وجہ سے ان الفاظ کے متعلق یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ اس دوسری زبان کے لفظ ہی نہیں ہیں.وہ کثرت استعمال کی وجہ سے دوسری زبان کا جزو بن جاتے ہیں اور اسی زبان کا لفظ سمجھے جاتے ہیں.مثلًا اردو میں اگر متداول اور رائج العام لفظ انگریزی کا بولا جائے تو یہی کہیں گے کہ اس لفظ کا بولنے والا فصیح اردو بول رہا ہے یہ نہ کہیں گے کہ انگریزی الفاظ کی وجہ سے اس کی اردو خراب ہو گئی ہے.ہاں کثرت سے اور غیر مروج الفاظ کا استعمال ہو تو وہ قابل اعتراض ہوتا ہے.عربی زبان کے اُم الْا َلْسِنہ ہونے کی وجہ سے اس کے الفاظ کثرت سےغیر زبانوں میں پائے جاتے ہیں لیکن اس کے علاوہ آپس کے میل جول کی وجہ سے بھی ہر زبان میں دوسری زبان کے الفاظ آجاتے ہیں اور عربی زبان اس سے مستثنیٰ نہیں ہو سکتی.اور اگر ایسا لفظ عربی زبان میں پایا جائے تو اس کا استعمال غیر فصیح نہ ہو گا نہ اس کلام کو جس میں وہ پایا جائے وہ غیر عربی بنا دے گا.شیکسپیئر مشہور انگریز ادیب ہے اس کی کتب میں بھی بہت سے فرانسیسی زبان کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں مگر اس کی وجہ سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ شیکسپیئر کی کتب غیر فصیح انگریزی میں ہیں.اسی طرح اگرقرآن کریم کسی غیر زبان کا لفظ لے آئے.جو عربوں میں استعمال ہو چکا ہو اور عربوں نے اس کو پسند کر لیا ہو تو یہ بات اس لفظ کے عربی ہونے کے خلاف ہر گز نہیں ہو سکتی.درحقیقت یہ مخالفت کا ایک مجنونانہ مظاہرہ ہے جس کے ماتحت بعض پرانے منافقین نے قرآن کریم پر اعتراض کیا.اور جس کے ماتحت آجکل کے یورپین مستشرق بھی اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن کریم عربی زبان میں نازل ہونے کا دعویٰ کرتا ہے مگر اس میں غیر زبانوں کے الفاظ بھی پائے جاتے ہیں اور پھر وہ ایسے الفاظ کی ایک فہرست پیش کر دیتے ہیں.ان میں سے بعض کے متعلق ہم یقیناً یہ ماننے کے لئے تیار ہیں کہ وہ عربی زبان کے الفاظ نہیں ہیں.مثلاً توراتؔ کا لفظ عربی زبان کا نہیں اور ہم اسے تسلیم کرتے ہیں یا کون مسلمان کہتا ہے کہ جبریل عربی زبان کا لفظ ہے.یہ لفظ اپنی موجودہ شکل میں عربی زبان کا لفظ نہیں.اِسی طرح میکائیلؔ کا لفظ عربی زبان کا نہیں.یا اِسحٰق کا لفظ ہے ہم کب اس کے غیر عربی ہونے سے انکار کرتے ہیں.اسی طرح عیسیٰؔ کا لفظ ہے یہ بھی عربی زبان کا نہیں بلکہ جیسس JESIS کا بگڑا ہوا تلفظ ہے.قرآن مجید میں غیر عربی الفاظ کے استعمال ہونے کی وجہ پس ہمیں اس سے ہر گز انکار نہیں ہے کہ قرآن کریم میں غیر زبانوں کے الفاظ پائے جاتے ہیں.اور اگر وہ ایسے الفاظ کی تلاش میں اپنا وقت صرف کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس طرح وہ قرآن اور اسلام پر حملہ کر سکیں گے تو وہ اپنے وقت کو بالکل ضائع کرتے ہیں.ہم اگر اُن کی بعض باتوں کا انکار کرتے ہیں تو محض اس لئے کہ بعض الفاظ عربی زبان کے ہی ہوتے ہیں مگر وہ زبردستی ان کو غیر زبانوں کے الفاظ قرار دے دیتے ہیں.اس وجہ سے انکار نہیں کرتے کہ قرآن مجید میں غیر زبان کا کوئی لفظ پایا ہی نہیں جا سکتا.ہمیں اُن پر اگر شکوہ پیدا ہوتا ہے تو اس لئے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں یا حد سے زیادہ غلُوّ کرتے ہیں اور عربی الفاظ کے متعلق بھی یہ ثابت کرنے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں کہ وہ غیر عربی الفاظ ہیں اُن کا یہ فعل ہمارے لئے باعثِ اعتراض ہوتا ہے ورنہ ہم خود تسلیم کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں غیر زبانوں کے الفاظ بھی پائے جاتے ہیں اور ہمارے نزدیک یہ بات ہرگز قابل اعتراض نہیں ہے.اس قسم کے الفاظ میں سے جن کو زبردستی غیرزبان کاقرار دیا جاتا ہے ایک سِجِّیْن کا لفظ بھی ہےہمارا دعویٰ ہے کہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے مگر وہ بلاوجہ اسے غیر زبان کا لفظ قرار دے دیتے ہیں یہ بات ہے جو وجہ اعتراض ہے ورنہ اگر ایک لفظ تو کیا اگر وہ پانچ سو لفظ بھی قرآن کریم میں سے ایسے نکال کر لے آئیں جو غیر زبانوں کے ہوں تو ہم کہیں گے کہ ان کے استعمال میں کوئی حرج نہیں.جب عربوں نے ان الفاظ کو اپنی زبان میں شا مل کر لیا اور اُن کو انہوں نے کثرت سے استعمال کرنا شروع کر دیا تو اس کے بعد عربی میں ان الفاظ کا پایا جانا ہر گز قابلِ اعتراض امر نہیں ہو سکتا.لوگ روزانہ سٹیشن پر جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں ٹکٹ دو.مگر کیا ٹکٹ ہماری زبان کا لفظ ہے؟ یا لوگ بازار میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں فونٹن پن دکھائو.کیا فونٹن پن اُردو زبان کا لفظ ہے؟ مگر باوجود اس کے کہ یہ دونوں الفاظ ہماری زبان کے نہیں جب کوئی شخص کہتا ہے کہ مجھے ٹکٹ دو یا فونٹن پن دکھائو تو سب لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اردو زبان بول رہا ہے کوئی اور زبان نہیں بول رہا.تو جو الفاظ زبان میںرائج ہو جاتے ہیں اُن کا استعمال کرنا ہرگز قابلِ اعتراض نہیں ہوتا.اسی طرح جوالفاظ اصطلاحی ہوتے ہیں یا جو الفاظ کسی قوم پر حُجّت کرنے کے لئے ضروری ہوتے ہیں ان کا بھی اصل صورت میں استعمال کرنا ہر گز قابل اعتراض امر نہیں ہوتا.یا مثلاً اسماء کو اُن کی اصل زبان میں ہی بیان کر دینا قطعًا کوئی ایسا امر نہیں ہے جو قابلِ اعتراض ہو.اگر کسی شخص کا نام کرشنؔ چند ہو تو یہ نہیں ہو گا کہ دوسری زبان میں ہم کرشن چند کا ذکر کرتے وقت اس نام کا ترجمہ کرنے لگ جائیں بلکہ ایسی حالت میں ہم کرشن چند نام ہی لکھیں گے اور یہ پروا نہیں کریں گے کہ یہ کسی اور ز بان کا لفظ ہے اور ہم کسی اور زبان میں بات کر رہے ہیں پس یہ ایک غلط اور بے معنی اعتراض ہے جو قرآن کریم پر کیا جاتا ہے.بالخصوص سِـجِّیْن کے متعلق ان کا اعتراض کرنا سراسر غلط ہے.سِـجِّیْن عربی زبان کا لفظ ہے.لُغت میں اس کے معنے موجود ہیں.عربی زبان میں اس کے اور اشتقاق بھی استعمال ہوتے ہیں.مجھے تحقیق کا موقع نہیں ملا ورنہ ممکن ہے اشتقاق کبیر میں بھی اس کا ثبوت مل جائے.بہرحال سِـجِّیْنکو غیر زبان کا لفظ قرار دینا ہر گز درست نہیں ہے.
Page 425
کے الفاظ قرار دے دیتے ہیں.اس وجہ سے انکار نہیں کرتے کہ قرآن مجید میں غیر زبان کا کوئی لفظ پایا ہی نہیں جا سکتا.ہمیں اُن پر اگر شکوہ پیدا ہوتا ہے تو اس لئے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں یا حد سے زیادہ غلُوّ کرتے ہیں اور عربی الفاظ کے متعلق بھی یہ ثابت کرنے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں کہ وہ غیر عربی الفاظ ہیں اُن کا یہ فعل ہمارے لئے باعثِ اعتراض ہوتا ہے ورنہ ہم خود تسلیم کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں غیر زبانوں کے الفاظ بھی پائے جاتے ہیں اور ہمارے نزدیک یہ بات ہرگز قابل اعتراض نہیں ہے.اس قسم کے الفاظ میں سے جن کو زبردستی غیرزبان کاقرار دیا جاتا ہے ایک سِجِّیْن کا لفظ بھی ہےہمارا دعویٰ ہے کہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے مگر وہ بلاوجہ اسے غیر زبان کا لفظ قرار دے دیتے ہیں یہ بات ہے جو وجہ اعتراض ہے ورنہ اگر ایک لفظ تو کیا اگر وہ پانچ سو لفظ بھی قرآن کریم میں سے ایسے نکال کر لے آئیں جو غیر زبانوں کے ہوں تو ہم کہیں گے کہ ان کے استعمال میں کوئی حرج نہیں.جب عربوں نے ان الفاظ کو اپنی زبان میں شا مل کر لیا اور اُن کو انہوں نے کثرت سے استعمال کرنا شروع کر دیا تو اس کے بعد عربی میں ان الفاظ کا پایا جانا ہر گز قابلِ اعتراض امر نہیں ہو سکتا.لوگ روزانہ سٹیشن پر جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں ٹکٹ دو.مگر کیا ٹکٹ ہماری زبان کا لفظ ہے؟ یا لوگ بازار میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں فونٹن پن دکھائو.کیا فونٹن پن اُردو زبان کا لفظ ہے؟ مگر باوجود اس کے کہ یہ دونوں الفاظ ہماری زبان کے نہیں جب کوئی شخص کہتا ہے کہ مجھے ٹکٹ دو یا فونٹن پن دکھائو تو سب لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اردو زبان بول رہا ہے کوئی اور زبان نہیں بول رہا.تو جو الفاظ زبان میںرائج ہو جاتے ہیں اُن کا استعمال کرنا ہرگز قابلِ اعتراض نہیں ہوتا.اسی طرح جوالفاظ اصطلاحی ہوتے ہیں یا جو الفاظ کسی قوم پر حُجّت کرنے کے لئے ضروری ہوتے ہیں ان کا بھی اصل صورت میں استعمال کرنا ہر گز قابل اعتراض امر نہیں ہوتا.یا مثلاً اسماء کو اُن کی اصل زبان میں ہی بیان کر دینا قطعًا کوئی ایسا امر نہیں ہے جو قابلِ اعتراض ہو.اگر کسی شخص کا نام کرشنؔ چند ہو تو یہ نہیں ہو گا کہ دوسری زبان میں ہم کرشن چند کا ذکر کرتے وقت اس نام کا ترجمہ کرنے لگ جائیں بلکہ ایسی حالت میں ہم کرشن چند نام ہی لکھیں گے اور یہ پروا نہیں کریں گے کہ یہ کسی اور ز بان کا لفظ ہے اور ہم کسی اور زبان میں بات کر رہے ہیں پس یہ ایک غلط اور بے معنی اعتراض ہے جو قرآن کریم پر کیا جاتا ہے.بالخصوص سِـجِّیْن کے متعلق ان کا اعتراض کرنا سراسر غلط ہے.سِـجِّیْن عربی زبان کا لفظ ہے.لُغت میں اس کے معنے موجود ہیں.عربی زبان میں اس کے اور اشتقاق بھی استعمال ہوتے ہیں.مجھے تحقیق کا موقع نہیں ملا ورنہ ممکن ہے اشتقاق کبیر میں بھی اس کا ثبوت مل جائے.بہرحال سِـجِّیْنکو غیر زبان کا لفظ قرار دینا ہر گز درست نہیں ہے.
Page 426
مَرْقُوْمٌ:مَرْقُوْمٌ رَقَمَ سے اسم مفعول ہے اور رَقَمَ الْکِتَابَ کے معنے ہیں اَعْجَمَہٗ وَ بَیَّنَہٗ.اس نے کتاب کو لکھا اور اس پر زیرزبر لگائی.اور رَقَمَ الثَّوْب کے معنے ہوتے ہیں خَطَّطَہٗ وَاَعْلَمَہٗ.اس نے کپڑے پر دھاریاں بنائیں اور نشان لگائے.نیز کہتے ہیں فُلَانٌ یَرْقَمُ فِی الْمَآئِ یُضْرَبُ مَثَلًا لِلْحَذِقِ فِی الْاُمُوْرِ یعنی فلاں شخص معاملات میں بڑا حاذق ہے.(اقرب) ضحاک کہتے ہیں کہ مَرْقُوْم کے معنے لغت حمیر میں مختوم کے بھی ہیں یعنی جس پر مُہر لگی ہوئی ہو.وَاَصْلُ الرَّقْمِ: اَلْکِتَابَۃُ اور یہ کہ رقم کے اصل معنے کتابت کے ہیں.(فتح البیان) تفسیر.اِنَّ كِتٰبَ الْفُجَّارِ لَفِيْ سِجِّيْنٍکے متعلق ایک اشکال اور اس کی تشریح یہاں بعض لوگوں نے سوال اٹھایا ہے کہ کِتَابُ الْفُجَّارِ فِیْ کِتَابٍ مَّرْقُوْمٍ کے معنے ہی کیا ہوئے؟ یعنی بتایا یہ گیا ہے کہ کتابِ فجارسجّین میں ہے اور پھر سجّین کی یہ تشریح کی گئی ہے کہ وہ کتابِ مرقوم ہے گویا دوسرے الفاظ میں اس کامطلب یہ ہوا کہ فجّار کی کتاب.کتاب میں ہے اور یہ ایک ایسا فقرہ ہے جو بالکل بے معنی ہے جس کا کوئی مفہوم ہی سمجھ میں نہیں آ سکتا.علامہ زمخشری نے بھی یہ سوال اٹھایا ہے اور پھر اپنی کتاب میں انہوں نے اس کا جواب بھی دیا ہے چنانچہ وہ کشافؔ میں لکھتے ہیں سجّین عام ہے اور کتاب الفجّار اس کا ایک باب ہے یعنی سجّین وہ کتاب ہے جس میں مشرک.کافر.منافق.فجّار سب کے اعمال لکھے جاتے ہیں اور اسی کو بغیر کسی قید کے کتاب مرقوم کہا گیا ہے کیونکہ اس میںہر برے آدمی کا ذکر ہے ( الکشاف زیر آیت ھذا)خواہ وہ فاجر ہو یا منافق ہو یا کافر ہو یا مشرک ہو لیکن کتاب الفجار میں صرف ایک خاص قسم کے گروہ کی شرارتوں ا ور ان کی بداعمالیوں کا ذکر ہے اور بتایا یہ گیا ہے کہ کتابِ فجّار بھی کتابِ سجّین میں شامل ہے گویا جزو کو کل کی طرف منسوب کیا گیا ہے پس اُن کے نزدیک کتاب الفجار میں جو کتاب کا لفظ آیا ہے وہ باب کے معنوں میں استعمال ہوا ہے اور کتاب مرقوم میں جو کتاب کا لفظ ہے وہ زیادہ وسیع معنوں میں استعمال ہوا ہے اور آیت کا مطلب یہ ہے کہ فجّار کا اعمال نامہ کتاب مرقوم کا ایک حصہ اور باب ہے.الواحدیؔ کہتے ہیں کہ کتابِ مرقوم کو سجّین کی تفسیر قرار دینا درست نہیں کیونکہ روایات سے سجّین کتاب معلوم نہیں ہوتی اس لئے کتابٌ مرقوم کو اِنَّ كِتٰبَ الْفُجَّارِ کا بیان سمجھنا چاہیے اور جملہ کی تقدیر یوں سمجھی جائے کہ ھُوَ کِتَابٌ مَّرْقُوْمٌ.( فتح البیان زیر آیت ھذا)گویا وہ لَفِيْ سِجِّيْنٍ.وَ مَاۤ اَدْرٰىكَ مَا سِجِّيْنٌ کو درمیان میں ایک جملۂ معترضہ قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں اصل فقرہ صرف اتنا ہے کہ اِنَّ کِتَابَ الْفُجَّارِ کِتَابٌ مَّرْقُوْمٌ مگر یہ معنے درست نہیں ہیں کیونکہ اس صورت میں سِجِّیْن بلاتفسیر رہ جائے گا جو محاورۂ قرآنی کے خلاف ہے.
Page 427
سجّین کے متعلق مفسّرین نے اپنے جن خیالات کا اظہار کیا ہے وہ درج ذیل ہیں:.لفظ سجین کی تشریح پہلے مفسرین کے نزدیک بعض نے اِنَّ كِتٰبَ الْفُجَّارِ لَفِيْ سِجِّيْنٍ کے یہ معنے کئے ہیں کہ سات زمینوں کے نیچے ایک بہت بڑی چٹان ہے جس کا نام سجّین ہے اس چٹان کے نیچے کفار کے اعمال نامے رکھے جاتے ہیں اور بعض کہتے ہیں سجّین کسی چٹان کا نام نہیں بلکہ سجّین نام ہے شیطان کے کلّوں کا.شیطان زمین کے نیچے لیٹا رہتا ہے جب کوئی کافر مر جاتا ہے تو فرشتے اُس کی روح کو آسمان پر لے جاتے ہیں.کافر کی روح دیکھ کر آسمان والے کہتے ہیں ہم اس روح کو نہیں رکھ سکتے اسے واپس لے جائو( فتح البیان زیر آیت ھذا) چنانچہ وہ اسے زمین کے نیچے لے جاتے ہیں جہاں شیطان لیٹا ہوا ہوتا ہے.شیطان نے تمام کفار کے اعمال نامے اپنے کلّے کے نیچے رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور اُس کا کلّہ اُن اعمال ناموں کی وجہ سے پُھولا ہوا ہوتا ہے جب کافر کی روح اس کے پاس پہنچتی ہے تو وہ اس کا اعمال نامہ بھی پہلے اعمال ناموں سے نتھی کر کے اپنے کلّے کے نیچے رکھ کر لیٹ جاتا ہے.اس قسم کی اَور بھی بعض لغو اور بے ہُودہ روایات تفسیروں میں پائی جاتی ہیں.ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہود بعض مسلمانوں سے تمسخر کیا کرتے تھے اور وہ مسلمان اپنی سادہ لوحی کے سبب اُن کی بتلائی ہوئی روایات کو آگے بیان کر دیتے تھے یہاں تک کہ بعض مفسّر انہیں اپنی تفاسیر میں درج کر لیا کرتے تھے حالانکہ یہود اسلام کے شدید دشمن تھے اُن سے قرآن کریم کی کسی آیت کے معنے پوچھنا کسی صورت میں درست نہ تھا مگر وہ یہودیوں کے پاس چلے جاتے اور پوچھتے کہ اس آیت کے معنے کیا ہیں وہ تمسخر کرتے ہوئے ایسی باتیں کہہ دیتے جو سرتاپا غلط اور بے بنیاد ہوتیں.چنانچہ تفاسیر میں ایسی بہت سی روایات پائی جاتی ہیں جن کا یہودی کتب میں بھی کوئی نشان نہیں ملتا.لیکن بعض روائتیں ایسی ہیں جو یہودی کتب سے مل جاتی ہیں.ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بعض دیانتدار یہودی تھے اور اپنی کتابوں میں سے جو کچھ بتاتے تھے سچ سچ بتا دیتے تھے لیکن بعض بالکل جُھوٹی باتیں مسلمانوں کو بتا دیا کرتے تھے اور مُسلمان اپنی جہالت سے اُن کو قرآن کریم کی آیات کی تفسیر سمجھ لیتے تھے.ابن کثیر والے نے ایک جگہ اسی قسم کی روایات کا ذکر کرتے ہوئے ایک نہایت ہی لطیف فقرہ لکھا ہے.وہ ایک روایت کے ذکر پر لکھتے ہیں کہ یہ ایسی ہی روایت ہے جیسے ابن عباسؓ سے بعض یہودی روایات مروی ہیں وہ یہودیوں سے اُن پر اعتماد کر کے سوال کر لیا کرتے تھے اور یہودی انہیں جو کچھ بتا دیتے تھے اس کو وہ حسن ظنّی کر کے سچا سمجھ لیتے تھے.مجھے ابن کثیرکے مصنّف کی یہ بات بڑی پسند آئی کہ اُس نے بڑی دلیری اور جرأت سے اس مسئلہ پر روشنی ڈالی ہے.سجّین کے متعلق جو روایات تفسیروں میں پائی جاتی ہیں وہ بھی ایسی ہی ہیں کہ ان کا یہودی کتب سے بھی پتہ نہیں چلتا.
Page 428
عجیب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جگہ صاف طور پر فرماتا ہے کہ سجّین کتابِ مرقوم ہے مگر بعض مفسر کہتے ہیں کہ یہ سات زمینوں کے نیچے ایک چٹان ہے یا شیطان کے کلّوں کو سجّین کہا گیا ہے.جہاں خدا تعالیٰ نے کوئی بات نہیں بتائی وہاں تو وہ جو چاہیں کہہ جائیں مگر جہاں خدا تعالیٰ سجّین کے معنے بتا رہا ہے وہاں بھی یہ کہنا کہ اس کے معنے وہ نہیں جو قرآن نے بتائے ہیں بلکہ اس کے کچھ اَور معنے ہیں بہت بڑی غلطی ہے حالانکہ لُغت میں سجّین کے معنے موجود ہیں اور کتاب کے معنے بھی موجود ہیں.سجّین کے متعلق لکھا ہے کہ اس کے معنے دائم اور شدید کے ہیں اور کتاب کے متعلق لکھا ہے مَا یُکْتَبُ فِیْہِ.یعنی لکھی ہوئی تصنیف (۲)اَلدَّوَاۃُ.دوات (۳)اَلتَّوْرَاۃُ.تورات (۴)اَلصَّحِیْفَۃُ.صحیفہ (۵)اَلْفَرْضُ.فرض (۶)اَلْحُکْمُ.حکم (۷)اَلْقَدَرُ.قضاءآسمانی.اندازہ (۸)وَفِی الْمِصْبَاحِ ’’وَ یُطْلَقُ الْکِتَابُ عَلَی الْمُنَزَّلِ‘‘ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی کتاب (اقرب) ان معنوں کے لحاظ سےاِنَّ كِتٰبَ الْفُجَّارِ لَفِيْ سِجِّيْنٍ کا ایک تو یہ مفہوم ہو گا کہ فُجَّار کے متعلق ہمارا جو حکم ہے وہ سجّین نامی کتاب میں ہے.دنیا میں بھی کتابوں کے مختلف نام رکھے جاتے ہیں.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس رجسٹر میں ان کا ذکر کیا گیا ہے اس کا نام سجّین ہے یعنی ان فجّار کا جو اعمال نامہ ہو گا اُس پر یہ ہیڈینگ ہو گا کہ ان کے ساتھ معاملہ دائمی اور سخت کیا جائے گا کیونکہ سجّین کے معنے دائم کے بھی ہیں اور شدید کے بھی.اور اگر کتاب کے معنے اَلْقَدَرُ کے لیں تو آیت کا مطلب یہ ہو گا کہ اُن کے متعلق ایک ایسا اندزہ کیا گیا ہے جو لَفِیْ سِجِّیْنٍ حالت دائمی اور شدّت میں ہو گا.وَ مَاۤ اَدْرٰىكَ مَا سِجِّيْنٌ اور یہ حالت دائمی اور شدّت کیا چیز ہے كِتٰبٌ مَّرْقُوْمٌ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا فیصلہ ہے جو لکھا ہوا ہے یعنی وہ ٹلے گا نہیں پس کِتٰبُ الْفُجَّارِ کے معنے ہوئے قَضَائُ اللّٰہِ فِی حَقِّ الْفُجَّارِ یا حُکْمُ اللّٰہِ فِیْ حَقِّ الْفُجَّارِ یا قَدَرُ اللّٰہِ فِیْ حَقِّ الْفُجَّارِ یعنی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ فجّار کے حق میںسجّین میں ہے یعنی اس دفتر میں ہےجس میں دائمی اور شدید عذاب والوں کا ذکر ہے ان معنوں کو جو لغت کے لحاظ سے ثابت شدہ ہیں اگر لے لیا جائے تو اس امر کی کوئی ضرورت ہی نہیں رہتی کہ شیطان کے کلّے کو چیر چیر کر اُس میں کفار کے نامۂ اعمال کو رکھا جائے یا زمین کے نیچے چٹانیں تلاش کی جائیں یہ سب بے معنی اور لغو باتیں ہیں.قتادہ.سعید بن جبیر.مقاتل اور کعب کی طرف یہ بات منسوب کی گئی ہے کہ انہوں نے کہا سجّین ساتویں زمین کے نیچے ایک چٹان ہے اُسے ہٹا کر اُس کے نیچے کتابِ فجار رکھی جاتی ہے.اس صورت میں وہ کہتے ہیں کہ کِتَابٌ مَّرْقُوْمٌ میں حذفِ مضاف ہے اور مراد یہ ہے کہ سِجِّیْنٌ مَّحَلُّ کِتَابٍ مَّرْقُوْمٍ ہے یعنی کفار کے اعمال ناموں کی جگہ سجّین ہے مگر ابوعبیدہؔ اور اخفشؔ اور مبرّدؔ اور زجّاجؔ جیسے نحویوں اور ادیبوں نے جن میں سے ابو عبیدہ اور مبرّد ادب کے
Page 429
بہت بڑے ماہر گزرے ہیں اور اخفش اور زجّاج نحو کے بہت بڑے ماہر گزرے ہیں لَفِیْ سِجِّیْنٍکے معنے لَفِیْ حَبْسٍ وَّضِیْقٍ شَدِیْدٍ کئے ہیں.یعنی فجّار کی منزل حبس وضیق شدید میں ہو گی.وہ کہتے ہیں لَفِیْ سِجِّیْنٍ اَیْ لَفِیْ مَکَانِ خَسَاسَۃٍ وَذِلَّۃٍ.خساست اور ذلّت اُن کا مقام ہو گا.(تفسیر القرطبی زیر آیت ھذا) اس صورت میں کِتَابٌ مَّرْقُوْمٌ سجّین کی صفت ان معنوں میں ہو گی کہ یہ شدّت اور حبس کا مقام ایک کتابِ مرقوم میں ہے یعنی ایک لکھا ہوا فیصلہ ہے جو ٹل نہیں سکتا.میرے نزدیک اس آیت کے جو صاف معنے ہیں وہ یہی ہیں کہ فجّار کا فیصلہ سجّین میں ہے جو ایک اٹل فیصلہ ہے یا یہ کہ سجّین ایک ایسا فیصلہ ہے جو کتاب مرقوم ہے یعنی اٹل ہے.اِس آیت کے معنے اِس بات پر بھی روشنی ڈالتے ہیں کہ غیروں سے معاملات کرنے کے لحاظ سے ہی جس کا اس سورۃ میں ذکر کیا گیا ہے.عیسائی قوم خراب نہ ہو گی بلکہ اس قوم میں فسق وفجور بھی ہو گا کیونکہ نام تبھی رکھا جاتا ہے جب کسی چیز کی کثرت پائی جائےپس فجّار کہہ کر بتا یا کہ اس قوم میں صرف یہی عیب نہیں ہو گا کہ وہ دوسری اقوام سے بے انصافی کرے گی بلکہ اور بھی کئی قسم کے معائب اور فسق و فجور میں یہ مبتلا ہو گی.اور اُن کے متعلق جو فیصلہ ہو گا وہ بڑا سخت اور لمبا ہو گا جس طرح ان کا معاملہ دوسری اقوام سے لمبا اور سخت تھا اور جس طرح ان کی فتح اور کامیابی لمبی ہو گی اسی طرح اُن کے ساتھ معاملہ بھی لمبا اور سخت کیا جائے گا.سجین اور علیین کا صحیح مفہوم پھر میرے نزدیک اس آیت کے ایک اورمعنے بھی ہیں جس کی طرف پہلے کسی مفسر کا خیال نہیں گیا اور وہ یہ کہ قرآن کریم کے دو حصّے ہیں.ایک حصّہ انذاری ہے اور ایک حصّہ تبشیری ہے کچھ حصہ میں تو دشمنانِ صداقت کی تباہیوں اور ان کی بربادیوں کا ذکر ہے اور کچھ حصہ میں مومنوں کی ترقیات اور اُن رحمتوں اور برکات کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اُن کے لئے مقدّر ہیں.پس میرے نزدیک سجّین اور علّیّین قرآن کریم کے دو حصّوں کا نام رکھا گیا ہے.علّیّین قرآن کریم کے وہ حصّے ہیں جن میں مومنوں کا ذکر ہے اور سجین قرآن کریم کے وہ حصے ہیں جن میں کافروں کا ذکر ہے.اس لحاظ سےاِنَّ كِتٰبَ الْفُجَّارِ لَفِيْ سِجِّيْنٍکے یہ نہایت ہی لطیف معنے ہوں گے کہ کس طرح ہو سکتا ہے یہ قوم تباہ نہ ہو.ان لوگوں کی تباہی اور بربادی کا فیصلہ تو قرآن کریم کے اُن حصوں میں موجود ہے جن میں آئندہ زمانہ کی تباہیوں کا ذکر کیا گیا ہے اور اُن حصوں میں اس قوم کی تباہی اور بربادی کی خبریں دی جا چکی ہیں.ضحاک کہتے ہیں کہ مَرْقُوْم کے معنے لغت حمیر میں مَخْتُوْمٌ کے ہیں اور یہ معنے اس مقام پر نہایت عمدگی سے چسپاں ہوتے ہیں کیونکہ کتابِ مختوم وہ ہے جو بدلتی نہیں جس کے فیصلے آخری اور قطعی ہوتے ہیں اور جن
Page 430
میں کسی قسم کی تبدیلی کا امکان نہیں گویا وہ خاتم الکتب ہے اور یہ خوبی قرآن کریم میں ہی پائی جاتی ہے.اگر یہ فیصلے کسی ایسی کتاب میں بیان ہوتے جو منسوخ ہو چکی ہوتی یا جس نے آئندہ کسی زمانہ میں منسوخ ہو جانا ہوتا تو یہ کہا جا سکتا تھا کہ جب یہ کتاب منسوخ ہو چکی یا آئندہ منسوخ ہونے والی ہے تو اس کے فیصلوں سے کیا خوف ہو سکتا ہے مگر یہ سجّین تو وہ ہے جو کتاب مرقوم ہے.یعنی یہ فیصلے اُس کتاب میں لکھے ہوئے ہیں جو کبھی تبدیل نہیں ہو سکتی اس لئے یہ فیصلے اٹل ہیں.اس صورت میںاِنَّ كِتٰبَ الْفُجَّارِ میں کتاب کو حکم کے معنوں میں لیا جائے گا اور مراد یہ لی جائے گی کہ اِن فجّار کا حکم سجِّین میں ہے اور سجّین کے معنے قرآن کریم کے انذاری حصہ کے ہوں گے.اسی طرح علّیّین سے مراد قرآن کریم کا وہ تبشیری حصہ لیا جائے گا جس میں مومنوں کی ترقیات کا ذکر آتا ہے.پس میرے نزدیک یہ ایک نہایت ہی لطیف اور واضح معنے ہیں جو اس مقام پر پوری طرح چسپاں ہوتے ہیں کیونکہ جیسے رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم خاتم النبیّین ہیں اسی طرح قرآن خاتم الکتب ہے اُس کے فیصلے اٹل اور قطعی ہیں خواہ وہ کفار کی تباہی کے متعلق ہوں یا مومنوں کی ترقی کے متعلق ہوں.ما اَدْرَاک اور ما یُدرِیکَ کےاستعمال میں فرق ابمَاۤ اَدْرٰىكَکے متعلق بھی ایک نکتہ یاد رکھنے کے قابل ہے.عربی زبان میں وَمَاۤ اَدْرٰىكَ اور مَایُدْرِیْکَ دونوں کے یہ معنے ہوتے ہیں کہ مَا تَدْرِیْ تُو اس بات کو نہیں جانتا.لیکن قرآن کریم پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اِن دونوں الفاظ کے استعمال میں فرق ہے.قرآن کریم میں مَآ اَدْرَاکَ اور مَایُدْرِیْکَ دونوں ہی الفاظ استعمال ہوئے ہیں.مَا اَدْرَاکَ بارہ جگہ آیا ہے اور مَایُدْرِیْکَ تین جگہ آیا ہے.چنانچہ مَآاَدْرَاکَ جن بارہ مقامات پر آیا ہے وہ یہ ہیں (۱)الحاقہ (۲)مدثّر (۳)مرسلات (۴)انفطار (۵)تطفیف (۶)تطفیف (۷)طارق (۸)بلد(۹)قدر (۱۰)قارعہ (۱۱)قارعہ (۱۲)ہُمزہ.ان سب مقامات پر مَا اَدْرَاکَ کے بعد اسم آیا ہے جیسے مَاالْحَاقَۃ.مَاسَقَرَ.مَایَوْمُ الدِّیْن.مَاسِجِّیْن.مَاعِلِّیُّوْن.مَاالطَّارِق.مَاالْعَقَبَۃ.مَالَیْلَۃُ الْقَدْرِ.مَاالْقَارِعَۃ.مَا ھِیَہ مَاالْحُطَمَۃ.اس کے برخلاف مَایُدْرِیْکَ جتنی جگہ آیا ہے کسی فعل کی طرف اُس میں اشارہ ہے.چنانچہ مَایُدْرِیْکَ قرآن کریم میں تین جگہ آیا ہے.سورۂ شوریٰ میں.احزاب میں.اور عبس میں.سورۂ شوریٰ میں آتا ہے وَمَایُدْرِیْکَ لَعَلَّ السَّاعَۃَ قَرِیْبٌ (شوریٰ:۱۸) سورۂ احزاب میں آتا ہے وَمَا یُدْرِیْکَ لَعَلَّ السَّاعَۃَ تَکُوْنُ قَرِیْبًا (احزاب :۶۴) سورۂ عبس میں آتا ہے وَمَایُدْرِیْکَ لَعَلَّہٗ یَزَّکّٰی(عبس:۴) اِن سب مقامات پر کسی وقوعہ کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے.د وسرا فرق یہ ہے کہ جہاں بھی مَااَدْرَاکَ آیا ہے وہاں اللہ تعالیٰ
Page 431
نے کسی سوال کا جواب دیا ہےمثلاً مَاالْقَارِعَۃ کے بعد یہ بتایا ہے کہ قارعہ کیا چیز ہے.مَاسَقَرَ کے بعد بتایا ہے کہ سقر کیا چیز ہے اور مَا یَوْمُ الْفَصْلِ یا مَا یَوْمُ الدِّیْن کے بعد بتایا ہے کہ یوم الفصل یا یوم الدین کیا چیز ہے گویا جہاں بھی مَااَدْرَاکَ آیا ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی سوال کا جواب دیا ہے.مثلاً (۱)سورۃالحاقہ میںمَا الْحَآقَّةُؕ کے بعد فرماتا ہے كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ وَ عَادٌۢ بِالْقَارِعَةِ.فَاَمَّا ثَمُوْدُ فَاُهْلِكُوْا بِالطَّاغِيَةِ.وَ اَمَّا عَادٌ فَاُهْلِكُوْا بِرِيْحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ (آیت ۴ تا ۷)یعنی ثمود اور عاد قوموں نے موعود عذاب کو جھٹلایا.سو اس کے بعد ثمود تو ایک بڑے زور کی کڑک کے صدمہ سے ہلاک کر دئے گئے.اور رہے عاد سو وہ بھی ایک سخت آندھی سے ہلاک کر دئے گئے.الغرض ان آیات میں اور بعد کی آیات میں فرعون اور پہلے معذّب لوگوں کا ذکر کر کے بتایا ہے کہ الحاقہ سے مراد وہ اٹل عذاب جن کو زبردست اقوام ساری کوششوں کے باوجود ٹلا نہیں سکتیں (۲)پھر سورۂ مدثّر میں مَاۤ اَدْرٰىكَ مَا سَقَرُ کے بعد اس کی تفسیر بھی کر دی کہ لَا تُبْقِيْ وَ لَا تَذَرُ.لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرِ.عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ (المدثر:۲۹ تا ۳۱) یعنی سقر ایسی چیز ہے کہ نہ وہ باقی رکھتی ہے اور نہ جلائے بغیر چھوڑتی ہے اور آدمی کے تن بدن کو جُھلس دیتی ہے اس پر اُنیس فرشتے متعیّن ہیں (۳) سورۂ مرسلات میں فرمایا ہے کہ وَ مَاۤ اَدْرٰىكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ ا ور پھر اس کا لمبا جواب دیتے ہوئے فرمایا هٰذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُوْنَ.وَ لَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُوْنَ۠.وَيْلٌ يَّوْمَىِٕذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ.هٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ١ۚ جَمَعْنٰكُمْ وَ الْاَوَّلِيْنَ (المرسلات:۳۶ تا ۳۹)یعنی یوم الفصل وہ دن ہو گا جب کہ گنہگار کوئی بات نہ کر سکیں گے اور نہ ان کو اجازت دی جائے گی کہ وہ کوئی عذر پیش کریں.خوب یاد رکھو کہ عذاب کو جھٹلانے والوں کے لئے تباہی ہی تباہی ہے اُس دن ہم اُن سے کہیں گے کہ یہی تو وہ یوم الفصل ہے جس میں تم کو اور پہلے لوگوں کو فیصلے کے لئے ہم نے جمع کیا ہے (۴)پھر سورۂ انفطار میں وَمَاۤ اَدْرٰىكَ مَا يَوْمُ الدِّيْنِکہا اور اس کی تفسیر یوں کہہ دی کہيَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْـًٔا (انفطار:۱۸ تا ۲۰) یعنی یوم الدین وہ دن ہے جس دن کوئی جان کسی جان کے کچھ کام نہ آسکے گی (۵)اسی طرح سورۂ تطفیف میں فرمایاوَ مَاۤ اَدْرٰىكَ مَا سِجِّيْنٌا ور اس کا جواب دیا کہكِتٰبٌ مَّرْقُوْمٌ.وَيْلٌ يَّوْمَىِٕذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ (تطفیف :۹ تا ۱۱) یعنی سجّین ایک اٹل حکم ہے (۶) پھر اسی سورۃ میں دوسری جگہ فرمایا وَ مَاۤ اَدْرٰىكَ مَا عِلِّيُّوْنَ اور اس کی تفسیر یوں فرما دی کہ كِتٰبٌ مَّرْقُوْمٌ.يَّشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُوْنَ۠(تطفیف:۲۰ تا ۲۲) یعنی علّیّون ایک ایسا حکم ہے جو ضرور پورا ہو گا اور اس کو مقرب لوگ دیکھیں گے.گویا سجّین وہ ہے کہ اُسے دیکھ کر کافر روئیں گے اور علّیّن وہ ہے کہ اس کو دیکھ کر مومن اُس کی طرف شوق سے جائیں گے.(۷) پھر سورۂ طارق میں مَا الطَّارِقُ کہہ کر اس کا جواب دیا النَّجْمُ الثَّاقِبُ (الطارق:۳،۴) کہ طارق ایک روشن چمکنے والا ستارہ ہے (۸)پھر سورۂ بلد میں فرمایا مَاالْعَقَبَۃُ اور اس کا جواب یہ دیا
Page 432
کہ فَكُّ رَقَبَةٍ.اَوْ اِطْعٰمٌ فِيْ يَوْمٍ ذِيْ مَسْغَبَةٍ.يَّتِيْمًا ذَا مَقْرَبَةٍ.اَوْ مِسْكِيْنًا ذَا مَتْرَبَةٍ(البلد:۱۳ تا ۱۷) یعنی عقبہ سے ہماری مراد یہ ہے کہ گردن کا غلامی یا قرض کے پھندے سے چھڑا دینا یا بھوک کے دن قرابت دار یتیم کو یا خاک افتادہ مسکین کو کھانا کھلانا (۹)اسی طرح اس بات کو حل کرنا تھا کہ مَالَیْلَۃُ الْقَدْرِ یعنی لیلۃ القدر کی کیا شان ہے.اِس لئے اس کے آگے جواب دے دیا کہ لَيْلَةُ الْقَدْرِ١ۙ۬ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ.تَنَزَّلُ الْمَلٰٓىِٕكَةُ وَ الرُّوْحُ فِيْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ١ۚ مِنْ كُلِّ اَمْرٍ.سَلٰمٌ١ۛ۫ هِيَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ (القدر:۳ تا ۶) یعنی لیلۃ القدر خیر وبرکت میں ہزار مہینے سے بھی بہتر ہے اس لیلۃ القدر میں ہر ایک انتظام کے لئے فرشتے اور روح خدا تعالیٰ کے حکم سے اُترتے ہیں اور وہ رات امن و سلامتی کی رات ہے اور یہ خیرو برکت صبح کےطلوع ہونے تک رہتی ہے.(۱۰)اسی طرح سورۂ قارعہ میں مَا الْقَارِعَۃُ کہہ کر اس کے جواب میں فرمایا يَوْمَ يَكُوْنُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوْثِ.وَ تَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوْشِ (القارعۃ:۴ تا ۶) یعنی قارعہ سے ہماری مراد ایک عظیم الشان حادثہ ہے اور جب وہ آئے گا اُس دن لوگ ایسے پڑے ہوئے ہوں گے جیسے پَردار چونٹیاں اور پہاڑ دُھنکی ہوئی رُوئی کی طرح ہوں گے (۱۱) پھر اسی سورۃ میں وَ مَاۤ اَدْرٰىكَ مَاهِيَہْ کہہ کر ھَاوِیَۃ کے بارے میں سوال کیا تھا اس کا یہ جواب دیا کہ نَارٌ حَامِیَۃٌ یعنی ہاویہ ایک شعلے مارنے والی آگ ہے (القارعۃ:۱۱،۱۲)(۱۲) پھر سورۂ ہُمزہ میں فرمایا وَ مَاۤ اَدْرٰىكَ مَا الْحُطَمَةُ اور اس کا یہ جواب دیا کہ نَارُ اللّٰهِ الْمُوْقَدَةُ.الَّتِيْ تَطَّلِعُ عَلَى الْاَفْـِٕدَةِ (ھمزہ:۶تا۸) یعنی حطمہ سے مراد اللہ کی وہ جلائی ہوئی آگ ہے جو داخل ہونے والوں کے دلوں کو جھانک رہی ہے.مَاۤ اَدْرٰىكَ کے بعد کسی سوال کے جواب کا ذکر ہوتا ہے اور مَاۤ یُدْرِیْكَ کے بعد جواب کو مبہم رکھا جاتا ہے پس قرآن کریم میں جہاں بھی مَاۤ اَدْرٰىكَ کا ذکر آیا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کسی سوال کا ضرور جواب دیا ہے.لیکن اس کے بالمقابل وَمَایُدْرِیْکَ کے جواب میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے بات کو لَعَلَّ سے شروع کیا ہے اور جواب کو مبہم اور ذو الوجوہ رکھا ہے.چنانچہ سورۂ شوریٰ میں فرمایا وَمَایُدْرِیْکَ لَعَلَّ السَّاعَۃَ قَرِیْبٌ پھر احزاب میں فرمایا وَمَایُدْرِیْکَ لَعَلَّ السَّاعَۃَ تَکُوْنُ قَرِیْبًا اور عبس میں فرمایا وَمَایُدْرِیْکَ لَعَلَّہٗ یَزَّکّٰٓی.گویا تینوں جگہ لَعَلَّ کا لفظ رکھا.دو جگہ توساعت کا ذکر کرکے فرمایا کہ تم نہیں جانتے وہ کب آنے والی ہے.اُس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ اپنے بندو ں کو اس کا علم نہیں دے سکتا.تیسری جگہ لَعَلَّہٗ یَزَّکّٰٓی کہہ کر پھر وہی صورت اختیار کی گئی ہے جو اوپر کے دو مقامات میں اختیار کی گئی تھی.لیکن مَاۤ اَدْرٰىكَ جہاں جہاں کہا گیا ہے وہاں سوال کا معیّن جواب دیا گیا ہے.
Page 433
مَاۤ اَدْرٰىكَ اور مَایُدْرِیْکَ کے اس فرق سے قرآن کریم کی فصاحت کا پتہ چلتا ہے.اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جہاں تک لغت کا سوال ہے اُس نے دونوں کو ہم معنیٰ قرار دیا ہے اور دونوںکے معنے یہ لکھے ہیںکہ مَاتَدْرِیْ.تُو نہیں جانتا.اور یہ بات درست بھی ہے کہ دونوں کے یہی معنےہیں مگر سوال یہ ہے کہ وجہ کیا ہے کہ قرآن کریم نے ایک سے عدمِ علم کی طرف اشارہ کر کے علم عطا کر دیا ہے اور دوسرے سے عدم علم کی خبر دے کر ابہام کو قائم رکھا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ گو لغت نے دونوں کو ایک قرار دیا ہے مگر صیغہ کے لحاظ سے مَاۤ اَدْرٰىكَ ماضی کا صیغہ ہے اور مَایُدْرِیْکَ مضارع کا صیغہ ہے.ا ور گو استعمالِ عام میں اَدْریٰ اور یُدْرِیْ دونوں کے ایک معنی کر دئے گئے ہیں مگر قرآن کریم نے ان دونوں میں فرق کیا ہے.ا ور اس کی وجہ یہ ہے کہ ماضی کا صیغہ یقین پر دلالت کرتا ہے کیونکہ جو واقعہ ہو چکا وہ بہرحال قطعی اور یقینی ہوتا ہے.لیکن مضارع محض توقع پر دلالت کرتا ہے اس لئے قرآن کریم نے بھی ان دونوں صیغوں کے استعمال میں اس فرقِ لطیف کو ملحوظ رکھا اور جس امر کو بتانا تھا اُسے ماضی کے صیغہ وَ مَاۤ اَدْرٰىكَ کے بعد رکھا اور جسے ابھی کچھ عرصہ کے لئے مبہم رکھنا تھا اُسے مَایُدْرِیْکَ کے الفاظ کے بعد رکھا.تاکہ مضارع کی طرح اُس کا علم بھی مبہم اور غیر یقینی رہے کیونکہ مضارع کا صیغہ اپنے اندر یقین نہیں رکھتا بلکہ محض توقع رکھتا ہے.چنانچہ دیکھ لو ہم کہتے ہیں یَذْھَبُ وہ جائے گا مگر اس میں یقینی خبر نہیں ہوتی کہ وہ ضرور جائے گا کیونکہ ہمیں کیا پتہ کہ وہ جائے گا یا مر جائے گا یا بیمار ہو جائے گا یا قید ہو جائے گاپس جس خبر کو یقینی کرنا مقصود نہ تھااُسے اللہ تعالیٰ نے مضارع کے الفاظ کے بعد رکھا اور جس بات کا یقینی علم دینا تھا اُسے ماضی کے الفاظ کے بعد رکھا.گویا اس طرح لُغت میں ایک لطیف فرق جو الفاظ کے مناسب حال ہے پیدا کر دیا جسے پہلے ادیب مدنظر نہ رکھتے تھے.وَيْلٌ يَّوْمَىِٕذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَۙ۰۰۱۱الَّذِيْنَ يُكَذِّبُوْنَ بِيَوْمِ اُس دن جھٹلانے والوں کے لئے عذاب (ہی عذاب) ہے (اُن کے لئے) الدِّيْنِؕ۰۰۱۲ جو جزاء سزا کے دن کا انکار کرتے ہیں.تفسیر.اس آیت میں پہلی سورۃ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے.وہاں چونکہ فرمایا تھا کہ وَمَاۤ اَدْرٰىكَ مَا يَوْمُ الدِّيْنِاس لئے یہاں اس امر کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ اس قسم کے ظلم ہمیشہ انجام سے استغناء اور انکار کے نتیجہ
Page 434
میں پیدا ہوتے ہیں جب کوئی سمجھ لے کہ میرے بُرے اعمال کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا تو وہ ہمیشہ عاجل فائدہ کو مقدم کر لیتا ہے اور بُرائیوں میں ترقی کرتا چلا جاتا ہے.اگر ہر فرد اور قوم کو اپنا انجام یا د رہے تو یہ حالت کبھی پیدا نہ ہو.مگر افسوس اسی یقینی سبق سے بھی دنیا فائدہ نہیں اٹھاتی.افراد اپنے اعمال سے برباد ہوتے ہیں.اقوام اپنے اعمال سے بربادہوتی ہیں اور اُن کی آنکھوں کے سامنے پہلے لوگوں کی تباہی اور بربادی کے نظّارے ہوتے ہیں مگر باوجود اس کے بار بار افراد اور اقوام اس کے خلاف چل کر تباہ ہو جاتی ہیں.جیسے کہانیوں میں مقناطیس کے پہاڑ کا ذکر آتا ہے کہ جب جہاز اُس کے قریب پہنچتا تھا تو وہ رُک نہیں سکتا تھا جب تک اُس سے ٹکرا کر پاش پاش نہ ہو جاتا.اسی طرح معلوم ہوتاہے یَوْمُ الدِّیْنکی تکذیب اور انجام کو بھول جانا روائتی مقناطیس کا پہاڑ ہے کہ اُس کے سامنے آکر انسانی یا قومی زندگی کا جہاز مقابلہ کر ہی نہیں سکتا ضرور اُدھر کھنچا چلا جاتا ہے اور آخر اُس سے ٹکرا کر ٹوٹ جاتا ہے.درحقیقت ظالموں کو تباہ کرنے کا خدا تعالیٰ نے یہ سامان پیدا کیا ہے کہ وہ یَوْمُ الدِّیْن کو بھول کر اپنے ظلم میں بڑھتے چلے جاتے ہیں اور آخر اُسی ظلم کی چٹان سے ٹکرا کر ہلاک ہو جاتے ہیں.خدا تعالیٰ نے کافر کی جہنم اُس کے قلب اور دماغ میں ہی پیدا کی ہوئی ہوتی ہے اور آخر ایک دن اُس کو تباہ کرنے کا اسی میں سے سامان پیدا ہو جاتا ہے.وَ مَا يُكَذِّبُ بِهٖۤ اِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ اَثِيْمٍۙ۰۰۱۳ اور اس کا انکار نہیں کر سکتا مگر وہی جو حد سے نکلا ہوا (اور) سخت گنہگار ہو.حَلّ لُغَات.اِعْتِدَاء اِعْتِدَاء کے معنے ظلم کرنے اور حد سے نکل جانے کے ہوتے ہیں چنانچہ اِعْتَدَیٰ عَلَیْہِ اِعْتِدَاءً کے معنے ہوتے ہیں ظَلَمَہٗ.اُس نے فلاں پر ظلم کیا (اقرب ) مُعْتَدٍ.اِعْتَدیٰ سے اسم فاعل کا صیغہ ہے اس لئے مُعْتَدٍ کے معنے ہوں گے ظلم کرنے والا.اَثِیْمٌ.اَثِیْمٌ اَثِمَ سے اسم فاعل کا مبالغہ کا صیغہ ہے اور اَثِمَ کے معنے عَمِلَ مَالَا یَحِلُّ کے ہوتے ہیں یعنی اس نے ایسا کام کیا جو جائز نہیں تھا اور وضعِ لُغت کے لحاظ سے اَثِمَتِ النَّاقَۃُ الْمَشْیَ اِثْمًا کے معنے ہوتے ہیں اَبْطَأَتْ (اقرب) اونٹنی سُست چلی.پس اَثِیْمْ وہ ہوا جس نے وہ کام جو کرنا تھا نہ کیا.گویا اِثْم کا لفظ کمی پر دلالت کرتا ہے اور اِعْتِدَاء کا لفظ زیادتی پر دلالت کرتا ہے.تفسیر.فرماتا ہے تَکْذِیْبُ یَوْمُ الدِّیْنِ کے متعلق جو بات ہم نے بیان کی ہے وہ ایسی نہیں کہ ہم یونہی ظلماً کر دیتے ہوں.یوم الدین کو بھول جانا کوئی اتفاقی امر نہیں ہوتا اور پھر یہ بھی نہیں کہ ہم نے اُن کو علم نہ دیا ہو ہم نے
Page 435
انہیں علم بھی دیا ہوتا ہے وہ بھی خوب سمجھتے ہیں کہ ان کے اعمال کا نتیجہ اچھا نہیں نکل سکتا مگر پھر وہ کیوں یوم الدین کو بھول جاتے ہیں.مُعْتَدٍ اور اَثِیْمٍ میں فرق فرماتا ہے اس کی دو وجوہ ہیں اِعْتِدَاء اور اِثْم.یہ دو چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے انسان یوم الدین کو بھول جاتا ہے یعنی جو کام نہ کرنے والے ہوں ان کو وہ کر لیتا ہے اور جو کام کرنے والے ہوں اُن کو وہ نہیں کرتا.معتدؔ وہ ہے جو نہ کرنے والے کاموں کو کرے اور اثیمؔ وہ ہے جو کرنے والے کاموں کو نہ کرے.یوں اِثم کے عام معنے گناہ کے ہی ہوتے ہیں مگر کسی لفظ کے وضعِ لغت کے لحاظ سے مخصوص معنے اس جگہ ہوتے ہیں جہاں اُس کے مقابل کا لفظ آجائے.اگر خالی مُعْتَدٍ کا لفظ یہاں آ جاتا تو ہم اس کے معنے گناہ کے کرتے.چاہے وہ گناہ کسی بات میں زیادتی کا نتیجہ ہوتا یا کسی بات میں کمی کا نتیجہ ہوتا.اسی طرح اگر خالی اِثْیم کا لفظ آجاتا تواس کے معنے بھی ہم گناہ کے ہی کرتے.چاہے یہ گناہ زیادتی پر دلالت کرتا اور چاہے کمی پر.مگر چونکہ معتداور اثیم دونوں لفظ اکٹھے آگئے ہیں اس لئے ضروری ہے کہ دونوں کو ہم الگ الگ مفہوم کا حامل قرار دیں اور وہ مفہوم جیسا کہ اُوپر بتایا جاچکا ہے یہ ہے کہ اِثْم کا لفظ کمی پر دلالت کرتا ہے اور اعتداء کا لفظ زیادتی پر دلالت کرتا ہےاور اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ مضمون بیان فرماتا ہے کہ یوم الدین کی تکذیب ہمیشہ اعتداءؔ اور اثمؔ سے پیدا ہوتی ہے.پہلے انسان گناہ کرتا ہے اور جب اسے اپنے گناہ کے متعلق گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے کہ کہیں میں پکڑا نہ جائوں یا میری بدنامی نہ ہو اور اس فکر میں اس کی جان گھلنی شروع ہوتی ہے تو اس کا دوسرا قدم یہ ہوتا ہے کہ وہ کوشش کرتا ہے مَیں اپنے انجام کو بھول جائوں اور اس طرح میں اپنے دل کی خلش سے بچ جائوں.گویا یوم الدین کی تکذیب ایک شراب ہے جس کے نشہ میں مدہوش ہو کر وہ اپنے انجام سے مستغنی ہو جاتا ہے.جیسے غالب نے کہا ہے ؎ مے سے غرض نشاط ہے کس رُوسیاہ کو اک گونہ بیخودی مجھے دن رات چاہیے (دیوان غالب صفحہ ۶۸) یعنی انجام کا خیال اب میرے دل پر ہر وقت مستولی رہتا ہے اور اس فکر میں میری جان گھل رہی ہے.میں اس فکر سے بچنے کے لئے شراب پیتا ہوں تا کہ مجھ پر ہر وقت ایک بے خودی کی حالت طاری ر ہے اور انجام میری آنکھوں کے سامنے نہ آئے.اسی طرح تکذیب یوم الدین ایک قسم کی شراب ہے جب انسان اعتداء اور اِثم میں پڑھتا چلا جاتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ ان اعمال کا انجام وہ بھول جائے.چنانچہ وہ کبھی افیون کھا کر.کبھی شراب پی
Page 436
کر کبھی بھنگ اور چرس اور گانجا استعمال کر کے چاہتا ہے کہ ہر وقت مدہوش رہے اور اُس کا بُرا انجام اس کی آنکھوں کے سامنے نہ آئے یا اگر وہ شراب اور افیون استعمال نہیں کرتا تو علمی طور پر تکذیب یوم الدین شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ محض وہم ہے کہ مرنے کے بعد انسان دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور اپنے اعمال کے متعلق اسے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دِہ ہونا پڑے گا.گویا یا تو وہ مادی نشوں کے ذریعہ سے اپنے علم کو کمزور کرتا ہے اور یا پھر فلسفی نشوں سے وہ اپنے علم کو کُند کر دیتا ہے تاکہ وہ اس عذاب سے بچ جائے.یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ واقعہ میں اگر انسان اس پر غور کرے تو اُسے حیرت آجاتی ہے کہ کروڑوں لوگ اس مرض میں مبتلا ہیں اور اُن کے اس مرض کی وجہ سوائے اعتداءؔ اور اثم کے اور کچھ نہیں.وہ اعتداء اور اِثم میں بڑھتے چلے جاتے ہیں اور جب دیکھتے ہیں کہ اُن کا انجام بھیانک ہے تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے اس انجام کو بُھول جائیں.چنانچہ یا تو وہ افیون اور شراب وغیر ہ سے وہ اپنے اوپر مدہوشی طاری کر لیتے ہیں اور یا پھر فلسفی نشوں سے وہ یوم الدین کی تکذیب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ محض جھوٹ ہے کہ انسان مر کر دوبارہ زندہ ہو گا.غرض فرماتا ہے وہ پہلے اعتداء اور اثم کرتے ہیں اور جب اعتداء اور اثم میں بڑھ جاتے ہیں تو مادی یا دماغی نشوں سے یوم الدین کو بُھلا دیتے ہیں.اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اَور زیادہ اعتداءؔ اور اَور زیادہ اثم کرتے ہیں گویا اُن کی مثال بالکل اُس چیتے کی سی ہوتی ہے جس نے بھوک میں اپنی زبان چاٹنی شروع کر دی تھی اور رفتہ رفتہ اس کی تمام زبان کھائی گئی تھی.یہ لوگ بھی پہلے اعتداءؔ اور اثم کرتے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یوم الدین کو بُھلا دیتے ہیں.جب یوم الدین کو بھول جاتے ہیں تو اَور زیادہ اعتداء اور اثم کرتے ہیں اور یہ چکّر چلتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ اُن کے اعمال کا جہازاس کی ظلم کی چٹان سے ٹکرا کر پاش پاش ہو جاتا ہے.اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا قَالَ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَؕ۰۰۱۴ جب ایسے لوگوں کے سامنے ہمارے نشانات پڑھے جائیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو پہلے لوگوں کی نقل کردہ باتیں ہیں.حَلّ لُغَات.اَسَاطِیر اَسَاطِیرجمع ہے اور اس کا واحد اَلْاِسْطَارُ وَالْاُسْطَارُ وَالْاُسْطُوْرُ وَالْاُسْطِیْرُ ہے اور اسکے معنے ہوتے ہیں مَا یُسْطَرُ اَیْ یُکْتَبُ ہر وہ چیز جو لکھی جائے (اقرب) پس اَسَاطِیْر کے معنے ہوئے لکھی ہوئی باتیں وَتُسْتَعْمَلُ فِی الْحَدِیْثِ لَانِظَامَ لَہٗ عام محاورہ میں اَسَاطِیْر بے جوڑ باتوں کو بھی کہتے ہیں.اِسی طرح ایک معنے حکایت کے ہیں (اقرب) یہ وہی لفظ ہے جس سے انگریزی میں سٹوری بنا ہے اور سپین سے
Page 437
انگریزی زبان میں بدل کر آگیا ہے پس اس آیت کے معنے یہ ہوئے کہ جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں یعنی مُعْتَدٍ اور اَثِیْم کے سامنے.تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو پہلے لوگوں سے نقل کی ہوئی کچھ بے جوڑ سی باتیں ہیں یا یوں کہو کہ لغت کے لحاظ سے اس کے تین معنے بن جائیں گے (۱) پہلے لوگوں سے لکھی ہوئی یعنی نقل کی ہوئی کچھ باتیں ہیں (یہ معنی یَکْتُبُ سے لئے جائیں گے) (۲)یا پہلے لوگوں کے متعلق کچھ بے جوڑ سی باتیں ہیں (۳)یا پہلے لوگوں کی حکائتیں اور کہانیاں ہیں.تفسیر.قرآن کریم میں اساطیر الاولین کا الزام نو مقامات پر قرآن کریم میں اَسَاطِیْرُ الْاَوَّلِیْن کا الزام نو مقامات پر آتا ہے جو یہ ہیں (۱)انعام ع۳ ۹ (۲)انفعال ع ۴ ۸ ۱ (۳)نحل ع۳ ۹ (۴)مومنون ع۵ ۵(۵)فرقان ع ۱ ۶ ۱ (۶)نمل ع۶ ۲ (۷)احقاف ع۲ ۲ (۸)ن والقلم ع ۱ ۳ (۹)تطفیف ع ۱ ۸ (۱) سورۂ انعام میں پہلے اہل کتاب کا ذکر کیا ہے پھر کفار کا ذکر ہے اور فرماتا ہے حَتّٰۤى اِذَا جَآءُوْكَ يُجَادِلُوْنَكَ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْۤا اِنْ هٰذَاۤ اِلَّاۤ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ(انعام :۲۶) (۲) سورۂ انفال میں ہےوَ اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا قَالُوْا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَآءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هٰذَاۤ١ۙ اِنْ هٰذَاۤ اِلَّاۤ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ (انفال:۳۲) (۳)سورۂ نحل میںوَ اِذَا قِيْلَ لَهُمْ مَّا ذَاۤ اَنْزَلَ رَبُّكُمْ١ۙ قَالُوْۤا اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ.لِيَحْمِلُوْۤا اَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ١ۙ وَ مِنْ اَوْزَارِ الَّذِيْنَ يُضِلُّوْنَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ١ؕ اَلَا سَآءَ مَا يَزِرُوْنَ(النحل:۲۵،۲۶) (۴) سورۂ مومنون میں ہے قَالُوْۤا ءَاِذَا مِتْنَا وَ كُنَّا تُرَابًا وَّ عِظَامًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ۠.لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَ اٰبَآؤُنَا هٰذَا مِنْ قَبْلُ اِنْ هٰذَاۤ اِلَّاۤ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ(مومنون:۸۳،۸۴) (۵) سورۂ فرقان میں ہے وَ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْۤا اِنْ هٰذَاۤ اِلَّاۤ اِفْكُ ا۟فْتَرٰىهُ وَ اَعَانَهٗ عَلَيْهِ قَوْمٌ اٰخَرُوْنَ١ۛۚ فَقَدْ جَآءُوْ ظُلْمًا وَّ زُوْرًا.وَ قَالُوْۤا اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلٰى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَّ اَصِيْلًا(الفرقان:۵،۶) (۶) سورۂ نمل میں ہے وَ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْۤا ءَاِذَا كُنَّا تُرٰبًا وَّ اٰبَآؤُنَاۤ اَىِٕنَّا لَمُخْرَجُوْنَ.لَقَدْ وُعِدْنَا هٰذَا نَحْنُ وَ اٰبَآؤُنَا مِنْ قَبْلُ١ۙ اِنْ هٰذَاۤ اِلَّاۤ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ (النمل:۶۸،۶۹) (۷) سورۂ احقاف میں ہے وَ الَّذِيْ قَالَ لِوَالِدَيْهِ اُفٍّ لَّكُمَاۤ اَتَعِدٰنِنِيْۤ اَنْ اُخْرَجَ وَ قَدْ خَلَتِ الْقُرُوْنُ مِنْ قَبْلِيْ١ۚ وَ هُمَا يَسْتَغِيْثٰنِ اللّٰهَ وَيْلَكَ اٰمِنْ١ۖۗ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ١ۖۚ فَيَقُوْلُ مَا هٰذَاۤ اِلَّاۤ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ(احقاف:۱۸) (۸) سورۂ ن والقلم میں ہےاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا قَالَ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ پھر فرماتا ہے سَنَسِمُهٗ عَلَى
Page 438
الْخُرْطُوْمِ.(القلم:۱۶،۱۷) (۹) آخری مقام یہی سورۂ تطفیف ہے جو زیر بحث ہے.اِس میں فرماتا ہے وَ مَا يُكَذِّبُ بِهٖۤ اِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ اَثِيْمٍ.اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا قَالَ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ(تطفیف:۱۴) قرآن مجید کو اساطیر الاولین کہنے والوں کی تردید اِن آیات کو دیکھنے سے معلو م ہوتا ہے کہ سورۂ انعام کی آیت میں اَسَاطِیْرُ الْاَوَّلِیْنَ اِس ذکر میں ہے کہ پُرانی کتب کی پیشگوئیاں اور محمد رسول اللہ صلے اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کے نئے نشانات جب اُن کو دکھائے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو پُرانے زمانہ کی باتیں دُہرائی جاتی ہیں گویا پیشگوئیاں نہیں ہیں بلکہ پُرانی کتب کی باتوں کو دھوکا دینے والے طریق سے پیش کر کے مطلب حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے.مثلاّ یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ موسیٰ ؑ کی بات کو دیکھو جو فرعون کے سامنے ہوئی اور پھر فرعون کا انجام.گویا ہمیں ڈرایا جاتا ہے کہ فرعون نے موسیٰ ؑ کا مقابلہ کیا اور وہ تباہ ہو گیا اگر ہم بھی مقابلہ کریں گے تو تباہ ہو جائیں گے.حالانکہ تمہاری موسیٰ ؑسے کیا نسبت ہے.یا ابراہیم ؑ کا ذکر کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس کے دشمن تباہ ہوئے حالانکہ تمہاری ابراہیمؑ سے کیا نسبت ہے.اللہ تعالیٰ اِس کا جواب دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ جب آخری نتیجہ نکلے گا اُس وقت یہ لوگ کہیں گے کہ کاش ہم مخالفت نہ کرتے جیسا کہ فتح مکّہ کے وقت ہوا.مَیں نے اس کی مثال بھی دی تھی کہ عرب کے بڑے بڑے سرداروں کے بیٹے حضرت عمرؓ کی خدمت میں حاضر ہوئے وہاں اُن کی موجودگی میں پے در پے رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم کے غلام صحابہؓ حضرت عمرؓ کے ملنے کے لئے آئے.جب بھی کوئی صحابی آتا جو کسی وقت اُن کا یا اُن کے باپ دادا کا غلام رہ چکا تھا اور وہ لوگ اُس سے کئی قسم کے مشقّت طلب کام لیا کرتے تھے.تو حضرت عمرؓ اُن رئوسا ء مکّہ سے کہتے اِن کے لئے جگہ چھوڑ دو.یہاں تک کہ وہ ہٹتے ہٹتے جُوتیوں میں جا پہنچے اور پھر ناراض ہو کر وہاں سے اُٹھے اور باہر آ کر انہوں نے آپس میں کہا کہ آج ہماری کیسی ذلّت ہوئی ہے ایک نوجوان جو اُن میں سے زیادہ سمجھدار تھا کہنے لگا کہ یہ کس وجہ سے ذلّت ہوئی ہے آخر ہمارے باپ دادا کے کاموں کی وجہ سے ہی ہوئی ہے اگر ہمارے باپ دادا مخالفت نہ کرتے اور یہ لوگ اسلام کے لئے قربانیاں نہ کرتے تو ان کو عزّت کس طرح ملتی اور ہمیں یہ ذلّت کا دن آج کیوں دیکھنا پڑتا.یہی مضمون سورۂ انعام میں بیان کیا گیا ہے کہ اُس وقت یہ لوگ کہیں گے کہ کاش ہم مخالفت نہ کرتے مگر اُس وقت اِس افسوس کا کوئی فائدہ نہیں ہو گا.سورۂ انفال میں پیشگوئیوں کا ذکر نہیں بلکہ تعلیمات کا مقابلہ ہے اس لئے وہ کہتے ہیں کہ لَوْ نَشَآئُ لَقُلْنَا مِثْلَ ھٰذَا یہ تو پہلی کتب کی نقل ہے چاہیں تو ہم بھی ایسا کہہ سکتے ہیں.
Page 439
سورۂ نحل میں بھی یہی مضمون ہے کہ گزشتہ لوگوں کی باتوں کی نقل کرتے ہیں کیونکہ وہاں مضمون یہ آتا ہے کہ وَ اِذَا قِيْلَ لَهُمْ مَّا ذَاۤ اَنْزَلَ رَبُّكُمْ١ۙ قَالُوْۤا اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ اللہ تعالیٰ اُن کی توجہ اس طرف پھیرتا ہے کہ یہ نقل ہی سہی مگر محمد رسول اللہؐ اچھوں کی نقل کرتا ہے اور تُم بُروں کی نقل کر رہے ہو کیونکہ آگے فرماتا ہے قَدْ مَكَرَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَاَتَى اللّٰهُ بُنْيَانَهُمْ.(النحل :۲۷)ایسی باتیں پہلے لوگ بھی کرتے چلے آئے ہیں.گویا فرماتا ہے بیشک تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہہ دو کہ وہ موسیٰ ؑ کی نقل کرتا ہے یا ابراہیمؑ کی نقل کرتا ہے یا کسی اور نبی کی نقل کرتا ہے بہرحال اِس سے یہ ثابت ہو گا کہ وہ موسیٰ ؑیا ابراہیم ؑ کی نقل کر ر ہا ہے مگر تم اپنے اعمال کو دیکھو تم وہ کچھ کر رہے ہو جو فرعون نے کیا تھا یا موسیٰ ؑاور عیسٰی ؑ کے دشمنوں نے کیا تھا یا نوح ؑ کے دشمنوں نے کیا تھا.سو جس طرح پہلوں نے مخالفت کر کے نقصان اُٹھایا تھا تم بھی اُن کی نقل کر کے نقصان اُٹھائو گے مگر محمد رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم پر الزام تو اُن لوگوں کی نقل کاہے جو مقبولانِ بارگاہِ الٰہی تھے.اِس جگہ قیامت کا بھی ذکر ہے اور ساتھ ہی توحید کی تعلیم کا بھی.اور بتایا یہ گیا ہے کہ توحید اور قیامت کے متعلق محمد رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم جو تعلیم دیتے ہیں تم اُسے بے شک نقل کہہ لو مگر بہرحال یہ وہی تعلیم ہےجو مُوسٰیؑاور عیسٰیؑ نے دی.تم اس تعلیم کی مخالفت کرتے ہواس لئے تمہاری مثال وہی ہے جو فریسیوں اور فقیہوں اور نمرود اور شدّاد وغیرہ کی تھی.نقل کرنے والا آخر اُس کے ساتھ ہی رہے گا جس کی وہ نقل کرتا ہے پھر تمہیں خوشی کس بات کی ہے.سورۂ مومنون سے یہ واضح ہوتا ہے کہ وہاں قیامتِ اُخروی کا ذکر ہے.کافر کہتے ہیں کہ قیامت کا ذکر پہلے لوگ بھی کرتے چلے آئے ہیں مگر اب تک آئی نہیں.جب پہلے لوگ بھی اس کا ذکر کرتے رہے اور اُن کے کہنے سے آئی نہیں تو تمہارے کہنے سے قیامت کس طرح آجائے گی.اللہ تعالیٰ اِس کا جواب دیتا ہے کہ خدا قدرتوں والا ہے یہ سوال کہ قیامت نہیں آئی اس کے دو ہی معنے ہو سکتے ہیں.ایک یہ کہ خدا قیامت نہیں لا سکتا دوسرے یہ کہ قیامت اب تک کیوں نہیں آئی.فرماتا ہے خدا کے فعل تمہارے سامنے ہیں اُن کو دیکھ کر تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ قیامت نہیں آ سکتی.باقی رہا یہ کہ وہ نہیں آئی سو جب آئے گی آجائے گی یہ کیا سوال ہے کہ وہ اب تک نہیں آئی اپنے وقت پر یہ بات پُوری ہو جائے گی.سورۂ مومنون کی اِس آیت سے قیامت کے وعدے کا بھی ثبوت ملتا ہے اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ صرف اِس دُنیا کی قیامت کا ذکر قرآ ن کریم میں ہے اُن کی بھی تردید ہوتی ہے کیونکہ اِس دنیا کی قیامت کا وعدہ قرآن کریم میں تھا.مگر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَ اٰبَآؤُنَا هٰذَا مِنْ قَبْلُ اِنْ هٰذَاۤ اِلَّاۤ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ گویا وہ اپنے اباء کا بھی
Page 440
ذکر کرتے ہیں جس سے دوسری قیامت ہی مراد ہو سکتی ہے.قرآن کریم یہ نہیں کہتا کہ بعث بعد الموت کا کوئی وعدہ نہ تھا تم غلط کہتے ہو یا قیامتِ کُبریٰ کا کوئی وعدہ نہ تھا تم غلط کہتے ہو.بلکہ وہ اُن کے اعتراض کو اس جہت سے تسلیم کرتا ہے کہ ایسا وعدہ تھا اور دوسری جہت سے اِس کی تردید کرتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے کلام میں یہ بات ہے اور خدا بڑی قدرتوں والا ہے.پس اپنے وقت پر جا کر یہ بات پوری ہو جائے گی.سورۂ فرقان کی آیتوں سے ظاہر ہے کہ وہاں تعلیمات کا ذکر ہے اور الزام یہ لگایا گیا ہے کہ پُرانی تعلیمات کو نقل کر کے پیش کر دیا گیا ہے.اللہ تعالیٰ نے اِس کا جواب یہ دیا ہے کہ اس تعلیم میں جو قرآن کریم پیش کرتا ہے رازِ کائنات اور رازِ فطرت مخفی ہیں.اسرارِ آسمانی اور اسرارِ زمینی دونوں کو اِس میں کھول دیا گیا ہے یعنی خدا کا معاملہ جوبندوں سے ہوتا ہے اور بندوں کا معاملہ جو خدا سے ہوتا ہے اُس پر پُوری تفصیل سے روشنی ڈالی گئی ہے اور مختلف مواقع پر بندے جس فطرت کا اظہار کرتے ہیں اُس کا اس تعلیم میں اظہار ہے.پھر جس تعلیم میں تمام قسم کی فطرتوں کے راز بیان ہیں خواہ وہ عرب میں ہوں یا ہندوستان میں ہوں.یا امریکہ میں ہوں یا یورپ میں ہوں.اور ہر قسم کی فطری ضروریات کا سامان اُس میں موجود ہے.اُدھر خدا تعالیٰ کے تمام قسم کے سلوک جو بندوں سے ہوتے ہیں چاہے وہ پہلے ہوئے ہیں یا نہیں اُن سب کو اس میں بیان کیا گیا ہے تو تم ان میں سے کس کس تعلیم کو نقل قرار دو گے.اور کون سی سابق تعلیم ایسی ہے جس میں یہ سب باتیں پائی جاتی ہیں.پہلی کتابیں وہ تھیں جن کا دائرئہ ہدایت بہت محدود تھا.وہ محدود الز مان اور محدود الاوقات تعلیمات تھیں اور پھر صرف ایک ایک علاقہ کے لئے تھیں ساری دُنیا کے لئے نہیں تھیں.اِسی لئے اِن کتب میں ہر فطرت کا لحاظ نہیں رکھا گیا.تورات میں صرف یہودی قوم کو مدنظر رکھا گیا ہے باقی قوموں کو مدنظر نہیں رکھا گیا.اِسی طرح سارے زمانوں کو مدنظر نہیں رکھا گیا مگر قرآن وہ کتاب ہے جو ساری قوموں اور سارے زمانوں کے لئے ہے.وہ یہودیوںؔ کے لئے بھی ہے.وہ عیسائیوںؔ کے لئے بھی ہے وہ مسلمانوں کے لئے بھی ہے وہ ہندوئوں کے لئے بھی ہے.وہ یوروپین لوگوں کے لئے بھی ہے.وہ چینیوں کے لئے بھی ہے.وہ جاپانیوں کے لئے بھی ہے.وہ وحشیوں کے لئے بھی ہے اور غیر وحشیوں کے لئے بھی ہے.غرض کوئی قوم ایسی نہیں جس کی ہدایت کے لئے قرآن نہ آیا ہو اور کوئی زمانہ ایسا نہیں ہے جس میں قرآن کی ضرورت سے انکار کیا جا سکتا ہو.اِسی لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نہایت جامع ہدایات نازل فرمائی ہیں جو ہر فطرت کے مطابقِ حال ہیں اور ہر زمانہ میں اُن پر عمل کیا جا سکتا ہے.جب قرآن کریم کی یہ شان ہے تو یہ لوگ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ یہ قرآن پہلی کتابوں کی نقل ہے.
Page 441
سورۂ نمل میں فرمایا ہے وَ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْۤا ءَاِذَا كُنَّا تُرٰبًا وَّ اٰبَآؤُنَاۤ اَىِٕنَّا لَمُخْرَجُوْنَ.لَقَدْ وُعِدْنَا هٰذَا نَحْنُ وَ اٰبَآؤُنَا مِنْ قَبْلُ١ۙ اِنْ هٰذَاۤ اِلَّاۤ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ اِس آیت میں اُ س طرح کامضمون بیان ہوا ہے جس طرح سورۂ مومنون میں بیان کیا گیا تھا وہاں بھی فرمایا گیا تھا کہ قَالُوْۤا ءَاِذَا مِتْنَا وَ كُنَّا تُرَابًا وَّ عِظَامًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ۠.لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَ اٰبَآؤُنَا هٰذَا مِنْ قَبْلُ اِنْ هٰذَاۤ اِلَّاۤ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ پس جو مضمون سورۂ مومنون میں بیان کیا گیا تھا وہی ایک ادنیٰ تغیر سے سورۂ نمل میں بیان کیا گیا ہے.یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اُن کے اعتراض کو ردّ نہیں کیا بلکہ قُلْ سِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِيْنَ (النمل:۷۰ ) کہہ کر وہی جواب دیا گیا ہے جو سورۂ مومنون میں دیا تھا.اور اعتراض کو صحیح تسلیم کر کے اس کا ردّ بتایا ہے کہ یومِ آخر لازم و ملزوم ہے دُنیوی قیامت سے.جب یہ ہو گئی تو سمجھو کہ وہ بھی ضرور ہو گی.ساتویں آیت سورۂ احقاف کی ہے اُس میں آتاہے فَیَقُوْلُ مَا ھٰذَآ اِلَّآ اَسَاطِیْرُ الْاَوَّلِیْنَ مگر اس سے پہلے ہے وَ الَّذِيْ قَالَ لِوَالِدَيْهِ اُفٍّ لَّكُمَاۤ اَتَعِدٰنِنِيْۤ.....قَبْلِیْ وَھُمَا یَسْتَغِیْثٰنِ اللّٰہَ وَیْلَکَ اٰمِنْ.اِنَّ وَعْدَ اللّٰہِ حَقٌّ اِس جگہ پر بھی قیامت کبریٰ کا ذکر ہے اور اس کا انکار کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ پہلے لوگوں نے بھی کہہ دیا تھا کہ قیامت آئے گی قیامت آئے گی اور اب تم نے بھی اُس ذکر کو دُہرا دیا.آٹھویں آیت سورۂ ن والقلم کی ہے.اِس میں کفّار کی طرف سے پیشگویئوں کا انکار کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ گزشتہ نبیوںکے ذکر سے ناجائز فائدہ اٹھا کر ہمیں ڈرایا جاتا ہے.اللہ تعالیٰ اِس کا جواب یہ دیتا ہے کہ جب عملًا تم پر عذاب آجائے گا پھرتو نہ کہو گے یہ صرف گزشتہ نبیوں کے واقعات سے ہمیں ڈراتا ہے پھر تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ پیشگوئیاں ہیں یعنی جب یہ پیشگوئیاں ہیں تو نقل کس طرح ہو گئی.جب تمہاری ناک پر نشانِ ذلّت لگے گا.تم پر آسمان سے عذاب نازل ہو گا.تم دُنیا میں بالکل ذلیل اور حقیر ہو جائو گے اور اسلام ترقی کر جائے گا تب تمہیں معلوم ہو گا کہ یہ گزشتہ لوگوں کی کہانیاں ہیں یا پیشگوئیاں ہیں.نویں آیت یہی سورۂ تطفیف کی آیت ہے جو اِس وقت زیر بحث ہے.اِس میں تینوں باتوں کا ذکر ہے.تعلیمات کا بھی اور بعثِ قریب اور بعثِ بعید کا بھی کہ ان کو یہ لوگ غلط قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پُرانی تعلیمات ہیں یا پُرانی حکایات ہیں یا پُرانے لوگوں نے بھی اِسی طرح ڈرایا تھا مگر ہوا اس طرح نہیں.فرماتا ہے یہ دونوں امور پُورے ہو کر رہیں گے.بعثِ قریب بھی اور بعثِ بعید بھی اور اُن کا نقل کا الزام بھی درست نہیں ہے کیونکہ نقّال تو یہ بھی ہیں چنانچہاِنَّ كِتٰبَ الْفُجَّارِ لَفِيْ سِجِّيْنٍ کہہ کر اس بات کو واضح کیا ہے کہ جو پہلے انبیاء کے دُشمنوں کے حالات ہیں وہ
Page 442
محمد رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے کفار سے ملائو تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ انہی کے حالات لکھے ہوئے ہیں.پس فجّار جو کچھ کر رہے ہیں وہ پہلے کفار کی کتابوں میںمل جائیں گے.اس لئے نقل تو وہ بھی کرتے ہیں مگر سجّین کی اور محمد رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم بھی بے شک نقل کرتے ہیں مگر عِلّیّین کی.چنانچہ محمدرسول اللہ صلے اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کے اعمال پر اگر تم غور کرو تو وہ تمہیں موسیٰ ؑاور اور عیسٰیؑ اور ابراہیمؑ اور نوح ؑ اور دوسرے انبیاء میں نظر آ جائیں گے اور یہ سیدھی بات ہے کہ نیک نیک کی نقل کرے گا اور بُرا بُرے کے پیچھے چلے گا.پس یہ الزام بے حقیقت ہے اس میں گویا یوں جواب دیا کہ نقل کرنا بھی تو آسان کام نہیں.آخر وجہ کیا ہے کہ محمد رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے تو موسٰی کی نقل کر لی.عیسٰیؑ کی نقل کر لی.ابراہیمؑ کی نقل کر لی.نوح ؑ کی نقل کر لی.مگر تم نے نہ کی؟ آخر تم جو کہتے ہوکہ اُس نے نقل کر لی.نقل کرلی.تم بھی نقل کر لو.مگر تمہارا سجّین والوں کی نقل کرنا اور محمد رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کا عِلّیّین والوں کی نقل کرنایہ خود اپنی ذات میں محمد رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کی ایک خوبی کا ثبوت ہے الزام کی بات نہیں.اِس سوال کا ایک اور جواب سورۂ فرقان میں آ چکا ہے.اُوپر کے جوابات سے ظاہر ہے کہ اَسَاطِیْرُ الْاَوَّلِیْنَ کفّار نے تین مواقع پر کہا ہے.ایک انکارِ قیامت کے موقع پر یعنی جب بھی قیامت کا ذکر کیا جاتا وہ کہتے تھے کہ پہلے لوگ بھی ایسا ڈراوا جھوٹے طور پر دیتے رہے ہیں اور تم بھی یہ ڈراوا جھوٹے طور پر دے رہے ہو.پہلوں کی بات بھی جھوٹی نکلی اور تمہاری بات بھی جُھوٹی ہے اب تک تو قیامت آئی نہیں.اس موقع پر کفار پہلوں کو بھی جُھوٹا کہتے تھے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جھوٹا کہتے تھے کہ نہ پہلوں کی بات پُوری ہوئی اور نہ تمہاری بات پوری ہو گی.دوسرا موقعہ جب کفار اَسَاطِیْرُ الْاَوَّلِیْنَ کہہ کر الزام لگایا کرتے تھے وہ ہوتا تھا جب بعثِ قریب کا اُن کے سامنے ذکر کیا جاتا.جب اسلام کی ترقی اور اُس کے غلبہ کا ذکر کیا جاتا اور کُفر کی تباہی کی پیشگوئیاں کی جاتیں تواِس موقعہ پر بھی وہ اَسَاطِیْرُ الْاَوَّلِیْنَ کہہ دیا کرتے تھے.مگر اِ س موقعہ پر وہ پہلوں کو جُھوٹا نہیں قرار دیتے تھے بلکہ یہ کہتے تھے کہ پہلے راستبازوں کی زندگی کی مثالیں تم اپنے اُوپر چسپاں کر لیتے ہو اور اس طرح لوگوں کو مرعوب کرتے ہو حالانکہ تم سے وہ معاملہ نہ ہو گا کیونکہ وہ سچے تھے اور تم نعوذ باللہ جھوٹے ہویہ ایسی ہی بات ہے جیسے آج کل غیر احمدیوں کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ تم مرزا صاحبؑ کی صداقت ثابت کرتے ہوئے حضرت عیسٰی علیہ السلام کا نام کیوں لیتے ہو یا رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم کی مثالیں کیوں پیش کرتے ہو اُن کا اور تمہارا آپس میں جوڑ ہی کیا ہے کہ تم پہلے راستبازوں کی مثالیں دینی شروع کر دیتے ہو اور کہتے ہو کہ موسٰی نے بھی یوں کیا اور عیسٰیؑ نے بھی یوں کیا اور محمد رسول
Page 443
اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے بھی یوں کیا.یہی طریق رسول کریم صلے اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کے زمانہ کے مخالفین کا تھا.وہ بھی کہتے کہ تم تولوگوں کو مرعوب کرنے کے لئے پہلے مقدس لوگوں کی زندگی کی مثالیں اپنے اُوپر چسپاں کر لیتے ہو حالانکہ تم سے وہ معاملہ نہیں ہو گا.وہ سچّے تھے اور تم نعوذباللہ جُھوٹے ہو.تیسرا موقعہ اَسَاطِیْرُ الْاَوَّلِیْنَ کہہ کر الزام لگانے کا یہ ہوتا تھا کہ کفّار اسلام کی تعلیم کی مشابہت پہلے نبیوں کی تعلیم سے دیکھ کر کہہ دیا کرتے تھے کہ یہ تو پہلے لوگوں کی باتوں کی نقلیں ہیں.مثلًا قرآن کو دیکھا کہ اُس میں ایک تعلیم دی گئی ہے اور پھر وہی تعلیم اُنہیں یا موسٰیؑیا عیسٰیؑ کی کتاب میں نظر آجاتی ہے تو کہتے ہیں کہ پہلے بزرگوں کی تعلیمات کو تم نقل کر کے پیش کر دیتے ہو تمہاری اِس میں کیا خوبی ہے.گویا تعلیمات کی خوبی وہ تسلیم کرتے تھے.ان تعلیمات کے پیش کرنے والوں کی بزرگی کو بھی وہ تسلیم کرتے تھے.مگر رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ کا انکار کرتے تھے محض اس لئے کہ نقل سے کسی کی برتری ثابت نہیں ہوتی.اگر تم نے موسٰی کی تعلیم کی نقل کر لی ہے یا عیسٰیؑ کی تعلیم کی نقل کر لی ہے تو یہ کس طرح ثابت ہو گیا کہ تم اپنے دعویٰ میں سچّے بھی ہو.غرض اِن تین مواقع پر الگ الگ اعتراض ہیں اور الگ الگ معنوں میں کفّار نے اِس دلیل سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے کبھی وہ اَسَاطِیْرُ الْاَوَّلِیْنَ کے یہ معنے لیتے تھے کہ یہ پہلوں کی نقل کی ہوئی حکایتیں ہیں.کبھی کہتے کہ یہ پہلوں کے متعلق بے جوڑ باتیں ہیں یُونہی ان انبیاء کے واقعات اپنے اُوپر چسپاں کرنا شروع کر دیتے ہیں حالانکہ نہ کوئی تعلق ہوتا ہے نہ جوڑ ہوتا ہے نہ واسطہ ہوتا ہے.پھر کبھی اِن معنوں میں وہ اَسَاطِیْرُ الْاَوَّلِیْنَ کہا کرتے کہ یہ پہلوں کی لکھی ہوئی باتیں ہیں.یعنی جو تعلیمیں پیش کی جارہی ہیں وہ وہی ہیں جو موسیٰ ؑیا عیسٰیؑ یا اور انبیاء نے دیں کوئی نئی تعلیم اُن میں نہیں ہے.جب انکارِ قیامت کے موقعہ پر وہ ایسا کہتے تھے تو اُن کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ پہلے لوگوں نے بھی ایسے قصّے بنا لئے تھے اب تم نے بھی ویسی باتیں کہنی شروع کر دی ہیں نہ پہلے لوگوں کے کہنے کے بعد قیامت آئی اور نہ اب قیامت آسکتی ہے.وہ بھی جُھوٹا ڈراوا دیتے رہے اور تم بھی جُھوٹا ڈراوا دے رہے ہو.گویا وہ بھی جھوٹے اور تم بھی جھوٹے.جب وہ اَسَاطِیْرُ الْاَوَّلِیْنَ کا الزام اِ س طور پر لگایا کرتے تھے کہ پہلے لوگوں کے متعلق بے جوڑ باتیں کہی جاتی ہیں تو ان کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ یہ باتیں تو سچّی ہیں اور پہلے راستباز بھی سچّے تھے مگر تم یونہی اُن باتوں کو اپنے اُوپر چسپاں کرنے لگ گئے ہو حالانکہ وہ سچّے تھے اور تم جھوٹے ہو.تیسرے اَسَاطِیْرُ الْاَوَّلِیْنَ کا الزام وہ اِن معنوں میں لگایا کرتے تھے کہ پہلے بزرگوں کی تعلیمات کونقل کر کے
Page 444
پیش کر دیا جاتا ہے اِ س میں تمہاری کیا خوبی ہے.غرض کفار کے یہ تین اعتراض اساطیرؔ کے تین معنوں کے مطابق ہیں اور قرآن کریم نے بھی اُن کے الگ الگ جواب دئے ہیں.اس جگہ چونکہ تعلیمات کا بھی ذکر تھا اور بعث بعد الموت کا بھی اور بعث قومی کا بھی اس لئے یہاں جو جواب دیا گیا ہے وہ اِن تینوں مضمونوں پر مشتمل ہے.چنانچہ بعثِ قریب کا جو انکار تھا اُس کے متعلق فرماتا ہے کہ اقوامِ مغرب جو سمجھتی ہیں کہ اُن کو کوئی تنزل نہیں آئے گا آخر اِسی دُنیا میں گر جائیں گی.ذلیل ہو ں گی اور اسلام اُن کی جگہ لے لے گا اور یہ ثبوت ہو گا بعثِ بعد الموت کے قائم ہونے کا.گویا اِس ایک بعث سے دوسرے بعث کا ثبوت مل جائے گا.تیسری بات یہ تھی کہ یہ لوگ اسلام پر نقل کا الزام لگاتے تھے اس کا جواب یہ دیا کہ اِنَّ كِتٰبَ الْاَبْرَارِ لَفِيْ عِلِّيِّيْنَمحمد رسول اللہ ؐ بیشک نقل کرتا ہے مگر جب بھی کرتا ہے موسٰی اور عیسٰیؑ کی ہی کرتا ہے.یہ مان لو کہ وہ نقل کرتا ہے مگر آخر یہ کیا بات ہے کہ وہ جب بھی نقل کرتا ہے موسیٰ ؑاور عیسٰیؑ اور دوسرے انبیاء ؑ کی ہی کرتا ہے اور تم جب بھی نقل کرتے ہو فرعون اور اس کے ساتھیوں کی ہی کرتے ہو.پھر تمہارے مُنہ پریہ زیب کس طرح دیتا ہے کہ تم کہتے ہو محمد رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم جھوٹے ہیں آخربات کیا ہے کہ محمد رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ جب بھی پڑتا ہے موسٰی کے ہاتھ پر پڑتا ہے اور تمہارا ہاتھ جب بھی پڑتا ہے فرعون پر پڑتا ہے.وہ نبیوں کی تعلیمات پر چلتا ہے اور تم اُن نبیوں کی تعلیمات سے دُور بھاگتے اور شیاطین کے پیچھے جاتے ہوآخر کوئی مشابہت صحیحہ ہی ہے جو دونوں میں کام کر رہی ہے.اگر دونوں کی باتیں علّیّین کے ہمرنگ ہوتیں اور کفّار بھی انبیاء ؑکی سی باتیں کہتے تو معاملہ مشتبہ ہو جاتا کہ دونوں میں سے کون سچا ہے کیونکہ وہ بھی موسیٰ ؑکی بات کہتے اور یہ بھی موسیٰ ؑکی بات کہتا وہ بھی عیسٰیؑ کی بات کہتے اور یہ بھی عیسٰیؑ کی بات کہتا.اُن کے اعمال بھی موسیٰ ؑکی طرح کے ہوتےاور اُس کے اعمال بھی موسیٰ ؑکی طرح کے ہوتے.اُن کے اعمال بھی عیسٰیؑ کی طرح کے ہوتے ہیں اور اُس کے اعمال بھی عیسٰیؑ کی طرح کے ہوتے.مگر یہاں تو ایک بیّن فرق اور نمایاں امتیاز نظر آتا ہے.محمد رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور محمد رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کے اعمال موسٰیؑسے ملتے ہیں اور تمہارے اقوال اور تمہارے اعمال فرعون سے ملتے ہیں.یہ ابرارؔ کے قدم پر چلتا ہے اور تم فجّارؔ کے قدم پر چلتے ہو اور خود اپنے نبیوں کے خلاف تعلیمات دیتے ہو یہ ثبوت ہے اِس بات کا کہ محمد رسول اللہ صلے اللہ علیہ وآلہٖ وسلم نبیوں کے نقشِ قدم پر ہے اور تم اُ س کے دشمنوں کے قدم پر ہو.پس نقل کا الزام بالکل غلط ہے یہ نقل نہیں بلکہ مشابہت ہے اور مشابہت بھی علّیّین کی.اس لئے یہ مشابہت اس کی سچّائی کی علامت ہے.
Page 445
اِ س جگہ پر یہ بھی یاد رکھنے والی بات ہے کہ جہاں کفّارِ مکہ نے اساطیر الاوّلین کا الزام قرآن کریم پر لگایا تھا وہاں آج تیرہ سو سال کے بعد یوروپین لوگوں نے بھی محمد رسول اللہ صلے اللہ علیہ وآلہٖ وسلم پر یہی الزام لگایا ہے (ینابیع الاسلام) اور پادری ٹسڈل نے ’’ماخذقرآن‘‘ لکھ کر ثابت کیا ہے کہ قرآن دوسری کتابوں سے نقل کیا گیا ہے.سورۂ تطفیف میں چونکہ یوروپین قوموں کا ذکر ہے اس لئے یہ بھی ایک مشابہت ہے جو یوروپین لوگوں کی کفّارِ مکّہ سے ہے.کہ جو باتیں کفّار مکّہ نے کہی تھیں وہی اُنہوں نے کہنی شروع کر دیں اور اُن سے بھی خدا تعالیٰ نے ایسی کتابیں لکھوا دیں جن میں وہی اعتراض دُہرایا گیا ہے جو کفّارِمکّہ آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم پر کیا کرتے تھے.گویااِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا قَالَ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ میں یہ پیشگوئی مخفی تھی کہ آئندہ زمانہ میں جب عیسائی غالب آجا ئیں گے یہی الزام اسلام اور قرآن پر عائدکریں گے.چنانچہ ’’ماخذ قرآن‘‘ میں خصوصیّت سے اِسی موضوع پر بحث کی گئی ہے کہ قرآن دوسری کتابوں کی نقل ہے.اسی طرح اور بھی کئی کتابیں عیسائیوں کی طرف سے شائع ہو چکی ہیں جن میں قرآن کریم پر یہی الزام لگایا گیا ہے.الغرض فرماتا ہے اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا قَالَ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ یعنی جب اُن کے سامنے ہماری باتیں پیش کی جائیں گی تو وہ کہیں گے کہ یہ اساطیر الاوّلین ہیں یعنی یہ لوگ جو مکذّب بالدین ہیں جب اُن کے سامنے قرآن کریم کی تعلیم پیش کی جائے گی تو وہ کہیں گے کہ یہ کیا کتاب ہے اِس میں کچھ باتیں ویدؔ سے نقل کی گئی ہیں.کچھ تورات سے نقل کی گئی ہیں.کچھ انجیل سے نقل کی گئی ہیں.کچھ ژندواؔوستا سے نقل کی گئی ہیں.اس کا جوا ب اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں دیا ہے.لیکن اگر کوئی غور کرنے والا ہو تو یہی جواب کتنا واضح ہے کہ تم محمد رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم پر کیا الزام لگاتے ہو.محمد رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم تو وہ ہیں جنہوں نے پہلے سے تمہاری نسبت یہ خبر دے رکھی تھی کہ تم ایک زمانہ میں ایسا الزام لگائو گے.پس یہ الزام اُن کو جھوٹا ثابت کرنے والا نہیں بلکہ اُن کی صداقت کو اور بھی واضح کرنے والا ہے.كَلَّا بَلْ١ٚ رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ۰۰۱۴ ہر گز (ایسا) نہیں (جو وہ کہتے ہیں)بلکہ (اصل بات یہ ہے کہ) اُن کے دلوں پر اُس نے جو وہ کما چکے ہیں.زنگ لگا دیا ہے.حَلّ لُغَات.کَلَّا: مَعْنَاہُ الرَّدْعُ وَالزَّجْرُ یعنی کَلَّا کے معنے زجر کے بھی ہوتے ہیں اور دھتکارنے
Page 446
کے بھی ہوتے ہیں.اُردو میں اس کا ترجمہ کیا جائےتو یہ ہو گا کہ بس بس رہنے دو! یا اس کا ترجمہ ہو گا.ہوش سے بات کرو.کُلّیات ابی البقاء میں لکھا ہے وَقَدْ تَجِیُٔ بَعْدَ الطَّلَبِ لِنَفْیِ اِجَابَۃِ الطَّالِبِ.یہ کسی مطالبہ کے جواب میں آیا کرتا ہے یہ بتانے کے لئے کہ مطالبہ کرنے والے کی بات ہم ماننے کے لئے تیار نہیں.یعنی کبھی کبھی کَلَّا کا لفظ اِن معنوں میں استعمال ہوتا ہے یہ مطلب نہیں کہ ہمیشہ ہی ایسا ہوتا ہےوہ کہتے ہیں کہ یہ استعمال اُس وقت ہوتا ہے جبکہ مثلًا کسی نے تجھے کہا کہ اس اس طرح کام کرو.اور تم آگے سے جواب دو کہ کَلَّا اَیْ لَایُجَابُ لِذَالِکَ.یہ بات ایسی نہیں جسے کوئی مان نہ سکے.اور کبھی یہ بمعنے حقًا بھی استعما ل ہوتا ہے جیسے آتا ہے کَلَّا اِنَّ الْاِنْسَانَ لَیَطْغٰی (اقرب) یعنی سچّی بات یہ ہے کہ انسان تو سرکشی کرتا ہے.رَانَ: رَانَ الشَّیْ ئُ فُلَانًا وَعَلَیْہِ وَبِہٖ (یَرِیْنُ رَیْنًا وَرُیُوْنًا) کے معنے ہوتے ہیں غَلَبَ عَلَیْہِ (اقرب) گویا لفظ رَیْن تین طرح استعمال ہوتا ہے.یہ بھی کہتے ہیں کہ رَانَ الشَّیْئُ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ رَانَ عَلَی الشَّیْءُ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ رَانَ بِہٖ اور ان تینوں صورتوں میں اس کے معنے ہوں گے.اس پر غالب آگیا.نیز کہتے ہیں رَانَتِ النَّفْسُ.جس کے معنے ہوتے ہیں خَبُثَتْ وَغَثَتْ نفس گندہ ہو گیا یا فریب میں مبتلا کر دیا گیا.(اقرب) اَلرَّیْنُ کے معنے ہوتے ہیں صَدَأٌ یَعْلُوا الشَّیْئَ الْجَلِیَّ.وہ زنگ جو کسی چیز پر لگ جاتا ہے (مفردات) پس رَانَ کے معنے ہوں گے.زنگ لگ گیا.تفسیر.فرماتا ہے.اے قرآن مجید کو اساطیر الاوّلین کہنے والو! ہوش کی دوا کرو! سنبھل کر بات کرو! اِس بات کا احساس کرو کہ تم کس چیز کے متعلق الزام لگا رہے ہو!.بل کا عربی زبان میں دو معنوں کے لئے استعمال بَلْ کا لفظ جو اِس آیت میں استعمال ہوا ہے یہ تدارک کے لئے آتا ہے اور اس کے دو معنے ہوتے ہیں.اوّل.بَلْ کا لفظ ان معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے کہ (الف) اس سے پہلے بیان کی تردید اور بعد میں بیان ہونے والے مضمون کی تصدیق مقصود ہوتی ہے.اور (بَاء) کبھی بَلْ سے پہلے بیان کر دہ مضمون کی تصدیق اور بعد میں بیان کر دہ مضمون کی تردید مقصود ہوتی ہے.بَلْ سے پہلے بیان کردہ مضمون کی تردید اور بعد میں بیان کردہ مضمون کی تصدیق کی مثال یہی سورۂ تطفیف کی آیت ہے.اِس میں بَلْ سے پہلے جو مضمون بیان ہوا ہے یعنی کفّار کا الزام کہ قرآن کریم اساطیر الاوّلین ہے اس کی تردید کی گئی ہے اور بَلْ کے بعد جو مضمون بیان ہوا ہے.یعنی رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ اس کی تصدیق کی گئی ہے اور دوسرے استعمال یعنی پہلے کی تصدیق اور دوسرے کی تردید کی
Page 447
مثال سورۂ صٓ کی یہ آیت ہے.صٓ وَ الْقُرْاٰنِ ذِي الذِّكْرِ.بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِيْ عِزَّةٍ وَّ شِقَاقٍ(ص : ۲،۳) یعنی قرآن کریم کا ذِیْ الذِّکْر ہونا توسچا ہے مگر ان کا انکارجھوٹا ہے.اُن کے انکار کی یہ وجہ نہیں کہ قرآن کریم میں ذکر کی اہلیت نہیں بلکہ اُن کے انکار کی یہ وجہ ہے کہ یہ تکبّر اور صداقت سے تنفّر کی مرض میں مبتلا ہیں.دوسری مثال اس کی سورۂ ق کی آیت قٓ١ۚ۫ وَ الْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ.بَلْ عَجِبُوْۤا اَنْ جَآءَهُمْ مُّنْذِرٌ مِّنْهُمْ (ق:۲،۳)کی ہے اِس میں یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن کریم کے مجید ہونے میں شبہ نہیں لیکن اُن کا انکار اُن کی جہالت کی وجہ سے ہے اور وہ جہالت یہ ہے کہ یہ اپنے میں سے ایک مُنذر کے آنے پر متعجب ہیں اور اصل کلام پر غور ہی نہیں کرتے.دوم.دوسری قسم بَلْ کی یہ ہوتی ہے کہ وہ نہ پہلے مضمون کی تردید کرتا ہے نہ دوسرے کی بلکہ بغیر پہلے مضمون کی تردید کرنے کے وہ بَلْ کے بعد ایک زائد صداقت بتاتا ہے.جیسے سورۂ انبیاء رکوع ۱ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہےبَلْ قَالُوْۤا اَضْغَاثُ اَحْلَامٍۭ بَلِ افْتَرٰىهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ.(الانبیاء:۶) اِس میں ہر بَلْ پہلے کی بھی تصحیح کرتا ہے اور بعد کی بھی مثلًا پہلے بَلْ کے بعد ہے قَالُوْآاَضْغَاثُ اَحْلَامٍ اِس سے پہلے قرآن کریم میں کفّار کا یہ اعتراض مذکور ہوا ہے کہ اَفَتَاْتُوْنَ السِّحْرَ وَاَنْتُمْ تُبْصِرُوْنَ کہ کیا تم سحر پر ایمان لاتے ہو ایسی حالت میںکہ تم اپنی آنکھوں سے اُس کو دیکھ رہے ہو.اِس کے بعد فرماتا ہے بَلْ قَالُوْا اَضْغَاثُ اَحْلَامٍ یہاں بَلْ کا لفظ لا کر اللہ تعالیٰ نے پہلے مضمون کی تردید نہیں کی.یہ نہیں کہا کہ وہ سحر کا الزام نہیں لگاتے بلکہ ایک مزید بات یہ کہی ہے کہ وہ قرآن پر صرف سحر کا الزام ہی نہیں لگاتے بلکہ ایک زائد الزام یہ بھی لگاتے ہیں کہ وہ پراگندہ خوابیں ہیں.اس کے بعد پھر بَلْ کو دُہرایا ہے اور اس کے ساتھ ایک اور الزام بھی بیان کیا ہے اور مطلب یہ ہے کہ پراگندہ خوابوں کا ہی الزام نہیں لگاتے بلکہ اِفْتَرٰہٗ بھی کہتے ہیں یعنی نعوذ باللہ محمد رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے افتراء کر کے یہ کلام بنا لیا ہے.پھر بَلْ کا لفظ تیسری دفعہ دُہرایا ہے اور اس کے بعد ایک چوتھا الزام بیان کیا ہے کہ ھُوَ شَاعِرٌ وہ چوتھا الزام یہ لگاتے ہیں کہ یہ تو شاعر ہے دل لبھانے والی باتیں کر کے نوجوانوں کو ورغلا لیتا ہے.گویا ہر دفعہ بَلْ لا کر پہلے مضمون کی تردید کئے بغیر اُس پر ایک زائد بات بتائی کہ وہ صرف ایک الزام نہیں لگاتے.بلکہ یہ الزام بھی لگاتے ہیں اور وہ الزام بھی لگاتے ہیں اسی طرح قرآن کریم میں آتا ہے لَوْ يَعْلَمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا حِيْنَ لَا يَكُفُّوْنَ عَنْ وُّجُوْهِهِمُ النَّارَ وَ لَا عَنْ ظُهُوْرِهِمْ وَ لَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ.بَلْ تَاْتِيْهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ (الانبیاء:۴۰،۴۱) اس میں بھی بَلْ سے پہلے مضمون کی تصدیق کرتے ہوئے آگے ایک مزید بات بتائی ہے کہ علاوہ اس کے کہ عذاب اِس قدر سخت ہو گا کہ وُہ اُسے دُور نہیں کر سکیں گے.وہ ایسا اچانک آئے گا کہ دل دھڑک جائیں گے اور عقلیں ماری جائیں گی.
Page 448
اِس سورۃ میں بَلْ١ٚ رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ میں لفظ بَلْ کا استعمال اَسَاطِیْرُ الْاَوَّلِیْنَ کے الزام کی تردید کرنے کے لئے آیا ہے کہ قرآن کریم کے متعلق یہ الزام لگانا بالکل غلط ہے اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ خود جہالت میں مبتلا ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دلوں پر رَیْن لگ گیا ہے.جیسا کہ حل لغات میں بتایا جا چکا ہے رَیْن کے معنے غالب آجانے اور زنگ لگ جانے کے ہی ہیں.دلوں پر رین لگنے کی تشریح فراء کے نزدیک فرّاء کہتے ہیں کَثُرَتْ مِنْھُمُ الْمَعَاصِیْ وَالذُّنُوْبُ فَاَحَاطَتْ بِقُلُوْبِھِمْ فَذَالِکَ الرَّیْنُ یعنی رین کا مفہوم یہ ہے کہ اُن کے گناہ یا اُن کی نافرمانیاں اتنی بڑھ گئیں کہ اُن گناہوں اور نافرمانیوں نے اُن کے دلوں کا احاطہ کر لیا اور اُن کی اصلاح ناممکن ہو گئی.حسنؔ کہتے ہیں کہ ھُوَ الذَّنْبُ عَلَی الذَّنْبِ حَتّٰی یَعْمَی الْقَلْبُ یعنی رَین کے معنے گناہ پر گناہ کئے جانے کے ہیں یہاں تک کہ دل اندھا ہو جائے ( فتح البیان زیر آیت ھذا).گویا فراء کے نزدیک قرآن کریم نے رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ کے الفاظ اِن معنوں میں استعمال فرمائے ہیں کہ اُن کے گندے اعمال نے اُن کے دلوں کا احاطہ کر لیا اور حسن بصری یہ کہتے ہیں کہ اُن کے بُرے اعمال کی وجہ سے یعنی اس وجہ سے کہ بار بار گناہوں کا عمل اُن سے صادر ہوا.اُن کے دل صداقت کو معلوم کرنے کی قوت سے محروم ہو گئے.رین کے لفظ کا اس وقت استعمال جب کوئی گندے اعمال میں پھنس جائے اور نکل نہ سکے ابو زیدؔ کہتے ہیں کہ یُقَالُ قَدْرِیْنَ بِالرَّجُلِ رَیْنًا اِذَا وَقَعَ فِیْمَا لَا یَسْتَطِیْعُ الْخُرُوْجَ مِنْہُ وَلَا قِبَلَ لَہٗ بِہٖ ( فتح البیان زیر آیت ھذا)یعنی قَدْرِیْنَ بِالرَّجُلِ رَیْنًا ایک محاورہ ہے اور یہ محاورہ اُس وقت استعمال کرتے ہیں جب کوئی شخص ایسے گند میں مبتلا ہو جائے کہ نہ اُس سے نکل سکے اور نہ اُس کا مقابلہ کر سکے.اِس لحاظ سے رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ کے معنے یہ ہوں گے کہ اُن کے اعمالِ بد کی وجہ سے آخر وہ دن آ گیا کہ اگر وہ چاہیں بھی کہ ہم بدی سے نکل جائیں تو وہ نہیں نکل سکتے تھے.رین ،طبع اور اقفال میں فرق ابو معاذ نحوی کہتے ہیں کہ اَلرَّیْنُ اَنْ یَّسْوَدَّ الْقَلْبُ مِنَ الذُّنُوْبِ وَالطَّبْعُ اَنْ یُّطْبَعُ عَلَی الْقَلْبِ وَھُوَ اَشَدُّ مِنَ الرَّیْنِ وَالْاِقْفَالُ اَشَدُّ مِنَ الطَّبْعِ (تفسیر فتح البیان زیر آیت ھذا)یعنی رَین کے معنے گناہوں کی وجہ سے انسان کا دل سیاہ ہو جانے کے ہیں.وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں رَین کی جگہ طبعؔ کا لفظ بھی آتا ہے اور طبعؔ کے معنے یہ ہیں کہ اُن کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے.اِسی طرح قرآن کریم میں کفّار کے دلوں کے متعلق اقفالؔ یعنی تالوں کا لفظ بھی آتا ہے.وہ کہتے ہیں کہ طبعؔ کا لفظ رَینؔ سے زیادہ سخت ہے اور اقفالؔ کا لفظ طبع ؔ سے
Page 449
زیادہ سخت ہے.لیکن میرے نزدیک یہ بات درست نہیں.یہ تینوں لفظ یعنی رَینؔ طبعؔ اور اقفالؔ الگ الگ مضمون بیان کرنے کے لئے آئے ہیں.رَین اصل میں زنگ کو کہتے ہیں اور زنگ اس بات کا نام ہوتا ہے کہ جس چیز پر زنگ لگا ہے وہ اپنی ذات میں گُھلنی شروع ہو گئی ہے.زنگ اسی کو کہتے ہیں کہ کوئی باہر کی چیز اثر کر کے دوسری چیز میں تغیّر پیدا کر دیتی ہے.لوہے کو زنگ لگتا ہے تو اس کا بھی یہی مطلب ہوتا ہے کہ باہر سے نمی پہنچی اور اُس کا آکسائیڈ بننا شروع ہو گیا یا تانبہ COPPER کو زنگ لگتا ہے تو ا س کا بھی یہی مطلب ہوتا ہے کہ اُس میںبَیرونی اثرات کی وجہ سے تغیّر پیدا ہونا شروع ہو گیا ہے.پس رَین ؔ کا لفظ اس مفہوم پر دلالت کرتا ہے کہ کِسی چیز کے اندر تغیّر پیدا ہونا شروع ہو گیا ہے اور وہ اپنی ماہیت کو چھوڑ بیٹھی ہے.اس تغیّر کا اظہار کرنے کے لئے رینؔ کا لفظ بولا جاتا ہے لیکن طبعؔ کا لفظ اِس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اُس نے دوسرے کے نقش کو قبول کر لیا کیونکہ طبعؔکے معنے مُہر کے ہوتے ہیں.پس جب ہم طبعؔ کا لفظ بولتے ہیں تو ہمارا اس طرف اشارہ ہوتا ہے کہ اُس نے دوسرے کے نقش کو قبول کر لیا.اس کے مقابلہ میں جب ہم اقفالؔ کا لفظ بولتے ہیں تو ہمارا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب یہ چیز اپنے زور سے نہیںکُھل سکتی.خدا ہی اس کو کھولے تو یہ کُھل سکتی ہے.پس یہ تین قسم کی الگ الگ کیفیّتیں ہیں جن کے لئے رینؔ ،طبع اور اقفالؔ کے الفاظ استعمال کئے جاتے ہیں.یہاں رینؔ کا لفظ یہ بتانے کے لئے استعمال کیا گیا ہے کہ اُن پر بیرونی گناہوں کا اس قدر اثر ہوا ہے کہ قلب جو نیکی کامنبع تھا اُس کی ماہیت ہی بدل گئی ہےاور وہ اب بدی پر دلیر ہو گیا ہے لیکن طبعؔ میں یہ بتا یا گیا ہے کہ اُن کے دلوں پر گناہوں کا ٹھپّہ لگ گیا ہے یعنی وہ چوٹی کے گنہگار ہو گئے ہیں کیونکہ ٹھپّہ والی چیز معیاری چیزہوتی ہے.اور اقفال کے لفظ نے یہ بتایا کہ اُن کی حالت ایسی ہو چکی ہے کہ اب اللہ تعالیٰ ہی اُن کے دلوں کے تالے کھولے تو وہ کُھلیں گے کوئی انسان اُن کو کھولنے کی طاقت نہیں رکھتا یعنی آپ اپنی اصلاح کرنی اُن کے اختیار سے باہر ہو گئی ہے.رینؔ کے متعلق رسول کریم صلے اللہ علیہ وآلہٖ وسلم سے بھی ایک حدیث مروی ہے جو یہ ہے عَنْ اَبِیْ ھُرَیْرَۃَ عَنِ النَّبِیِّ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلَہٖ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ الْعَبْدَ اِذَا اَذْنَبَ ذَنْبًا نُکِتَتْ فِیْ قَلْبِہٖ نُکْتَۃٌ سَوْدَائُ فَاِنْ تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ صُقِلَ قَلْبُہٗ وَاِنْ عَادَ زَادَتْ حَتّٰی تَغْلُفُ قَلْبُہٗ فَذَالِکَ الرَّیْنُ الَّذِیْ ذَکَرَہُ اللّٰہُ سُبْحَانَہٗ فِی الْقُرْاٰنِ کَلَّا بَلْ رَانَ عَلٰی قُلُوْبِھِمْ.احمد.ترمذی.نسائی.ابن ماجہ اور ابن جریر وغیرہ سب نے بتغیّر الفاظ اس روایت کو بیان کیا ہے.حضرت ابوہریرہؓ کہتے ہیں رسول کریم صلے اللہ علیہ وآلہٖ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو نُکِتَتْ فِیْ قَلْبِہٖ نُکْتَۃٌ سَوْدَاءُ اس کے دل پر ایک سیاہ نکتہ ڈال دیا جاتا ہے.مطلب یہ کہ بدی کی رغبت
Page 450
اُس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے فَاِنْ تَابَ اگر وہ توبہ کر لے وَنَزَعَ اور اپنے نفس کو پیچھے کھینچ لے وَاسْتَغْفَرَا ور استغفار کرے تو صُقِلَ قَلْبُہٗ اُس کا دل صاف ہو جاتا ہے وَاِنْ عَادَ ا ور اگر وہ پھر گناہ کرے تو زَادَتْ حَتّٰی تَغْلُفَ قَلْبُہٗ یہ سیاہی بڑھتی چلی جاتی ہے یہاں تک کہ ایک دن اُس کے دل کو بالکل ڈھانپ لیتی ہے اس کے بعد رسول کریم صلے اللہ علیہ وآلہٖ وسلم نے فرمایا فَذَالِکَ الرَّیْنُ الَّذِیْ ذَکَرَہٗ اللّٰہُ سُبْحَانَہٗ فِی الْقُرْاٰنِ.یعنی اسی حالت کی طرف قرآن کریم نے رین کے لفظ سے اشارہ فرمایا ہے.بَلْ١ٚ رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ الخ میں ایک نفسیاتی نکتہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک زبردست نفسیاتی و اخلاقی نکتہ بتایا ہے اور وہ یہ ہے کہ ہر عمل اپنا اثر چھوڑتا ہے.ہر عمل کا اثر وہی نہیں جو اُس عمل کے ساتھ متعلق ہے بلکہ اس کے علاوہ اُس کا اثر انسا ن کے اخلاق اور اُس کی عقل اور اُس کے علم کے آئندہ ظہور پر بھی پڑتا ہے.جھوٹ بولنے کے چار اثر ایک شخص جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ سے تعلق رکھنے والا جو اثر ہے وہ یہ ہے.کہ اوّلؔ وہ دوسروں میں بدنام ہو جاتا ہے اس کا اعتبار جاتا رہتا ہے.خدا تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے عاجل یاآجل عذاب کا مستحق ہوتا ہے.جس کے خلاف جھوٹ بولا جاتا ہے وہ اس کا د شمن ہو کر اُس کے نقصان کے درپے ہو جاتا ہے پھر اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بعض راستباز دوست اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ تم جھوٹے آدمی ہو ہم تمہارے ساتھ دوستی نہیں رکھ سکتے یہ تو اُس جھوٹ کے طبعی اور منفرد اثرات ہیں مگر ان کے علاوہ ہر گناہ کا ایک اور اثر بھی ہوتا ہے جو انسان کے دماغ اور اُس کے دل پر پڑتا ہے.مثلًا میں نے جھوٹ کی مثال دی تھی.جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اُ سکے دماغ اور دل پر اس کا پہلا اثر یہ پڑتا ہے کہ جھوٹ سے نفرت کم ہو جاتی ہے اور آئندہ جھوٹ بولنا اُس کے لئے آسان ہو جاتا ہے یہی حال اَور گناہوں کا ہے.پہلی دفعہ چوری کرتے ہوئے یا پہلی دفعہ جھگڑا کرتے ہوئے یاپہلی دفعہ گالیاں دیتے ہوئے یا پہلی دفعہ فساد کرتے ہوئے یا پہلی دفعہ قتل کرتے ہوئے انسان ڈرتا ہے کہ اگر میں نے ایسا کیا تو کہیں پکڑا نہ جائوں یا لوگوں میں بدنام نہ ہو جائوں مگر جب ایک دفعہ وہ ایسا فعل کر لیتا ہے تو اُس کے دماغ پر ایسا اثر پڑتا ہے کہ نہ صرف بدی کی نفرت اُس کے دل سے کم ہو جاتی ہے بلکہ دوسری دفعہ جھوٹ بولنا یا دوسری دفعہ چوری کرنا یا دوسری دفعہ گالیاں دینا اور فساد کرنا اُس کے لئے آسان ہو جاتا ہے اور بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اِن افعال کو کرنا شروع کر دیتا ہے.دوسرا اثر انسان کے دماغ اور اُس کے دل پر یہ پڑتا ہے کہ بوجہ ایک بدی کے ارتکاب کے دوسری بدیوں سے بھی اُس کی نفرت کم ہو جاتی ہے جو شخص چوری کرتا ہے اُس کے لئے اور جرائم کا ارتکاب نسبتًا آسان ہو جاتا ہے کیونکہ چوری کا فعل خدا تعالیٰ کی نافرنی کا احساس کم کر دیتا ہے.یہی حال
Page 451
جھوٹ اور دوسرے گناہوں کا ہے ہر گناہ اپنی ذات میں بھی بُرا ہوتا ہے لیکن ہر گناہ کا ایک خارجی اثر یہ ہوتا ہے کہ اور گناہوں سے نفرت کم ہو جاتی ہے اور خدا تعالیٰ کی نافرمانی میں انسان بڑھتا چلا جاتا ہے.تیسرا اثر اس کا یہ پڑتا ہے کہ بوجہ خود ارتکابِ بدی کے انسان دوسروں پر بھی بدظنی کرنے لگ جاتا ہے اور وہ خیال کرتا ہے کہ جب میں نے یہ فعل کیا ہے تو دوسرے بھی ایسا ہی کرتے ہوں گے.ایک شخص سچ بول رہا ہوتا ہے مگر وہ سمجھتا ہے کہ دنیا میںسچ کون بولتا ہے یہ بھی جھوٹ ہی بول رہا ہے اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ خود جھوٹ بولنے کا عادی ہوتا ہے.اس طرح وہ صداقت کے معلوم کرنے سے محروم ہو جاتا ہے اور بجائے سچ سے فائدہ اٹھانے کے غلط محرّکات دوسروں کے افعال کی طرف منسوب کر دیتا ہے.سچائی اس کے سامنے پیش کی جاتی ہے مگر وہ اس پر غور کرنے کی بجائے اس کو ردّ کر دیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ جس طرح میں جھوٹ بول رہا ہوں اسی طرح یہ بھی جھوٹ بول رہا ہے جس طرح میں فریب سے کام لیتا ہوں اسی طرح فلاں بھی فریب کرتا ہے.چوتھا اثر اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ گناہوں کے نتیجہ میں صادقوں کی معیّت سے محروم ہو جاتا ہے کیونکہ اُس کے نزدیک کوئی صادق ہوتا ہی نہیں.سب لوگوں کو وہ اپنی طرح جھوٹا سمجھتا ہے اور صادق بھی اس کی معیّت سے پرہیز کرنے لگ جاتے ہیں.یہ وسیع مضمون جو ساری دنیا کی نیکی اور بدی کے لئے بطور جڑ کے ہے اور جو دنیا کے اخلاق کی تباہی کا انکشاف کر رہا ہے.قرآن کریم نے اس چھوٹے سے فقرہ میں بیان کر دیا ہے کہ کَلَّا بَلْ رَانَ عَلٰی قُلُوْبِھِمْ مَّا کَانُوْا یَکْسِبُوْنَ.ہر کسب اپنے براہ راست نتیجہ کے علاوہ ایک اور نتیجہ بھی پیدا کر دیا کرتا ہے جو یہ ہے کہ وہ کسب انسان کی قوتِ عقلیہ اور قوتِ علمیہ اور قوتِ فکریّہ کو مار دیتا ہے اور اسی کا نام رینؔ ہے.كَلَّاۤ اِنَّهُمْ عَنْ رَّبِّهِمْ يَوْمَىِٕذٍ لَّمَحْجُوْبُوْنَؕ۰۰۱۶ثُمَّ یوں نہیں (جس طرح وہ کہتے ہیں بلکہ) اس دن وہ یقیناً اپنے رب کے سامنے آنے سے روکے اِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيْمِؕ۰۰۱۷ثُمَّ يُقَالُ هٰذَا الَّذِيْ كُنْتُمْ جائیں گے.پھر وہ ضرور جہنّم میں داخل ہوں گے.پھر (اُن سے) کہا جائے گا یہی تو وہ (انجام) ہے
Page 452
بِهٖ تُكَذِّبُوْنَؕ۰۰۱۷ جس کا تم انکار کرتے تھے.تفسیر.یہاں کَلَّا تیسری دفعہ آیا ہے.پہلے فرمایا تھاكَلَّاۤ اِنَّ كِتٰبَ الْفُجَّارِ لَفِيْ سِجِّيْنٍ.پھر فرمایا تھا كَلَّا بَلْ١ٚ رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ.اب فرماتا ہےكَلَّاۤ اِنَّهُمْ عَنْ رَّبِّهِمْ يَوْمَىِٕذٍ لَّمَحْجُوْبُوْنَ اس کے بعد آگے آئے گا كَلَّاۤ اِنَّ كِتٰبَ الْاَبْرَارِ لَفِيْ عِلِّيِّيْنَؕ شاید اتنا قریب قریب کَلَّا کا استعمال قرآن کریم میں اور کسی جگہ نہیں ہوا.یہ چند آیات ہیں مگر ان چند آیات میں ہی چار جگہ کَلَّا استعمال کیا گیا ہے.میں بتا چکا ہوں کہ کَلَّا کے معنے روعؔ اور زجرؔ کے ہیں پس کَلَّا کا جو اس جگہ تکرار کیا گیا ہے اُس میں شدّتِ عذاب کی طرف اشارہ ہے.مسیحیوں کے متعلق حضرت مسیح کی دعا اور اس کا نتیجہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مسیحیوں کی نسبت فرمایا تھا کہ فَمَنْ يَّكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَاِنِّيْۤ اُعَذِّبُهٗ عَذَابًا لَّاۤ اُعَذِّبُهٗۤ اَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ (المائدہ:۱۱۶) یعنی جب حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لئے مائدہ مانگا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں دے تو دوں گا مگر اس نعمت کا انکار نہایت خطرناک نتائج پیدا کرنے والاہو گا.چونکہ تم نے یہ دعا کی ہے کہ تمہاری قوم کو دنیا میں ترقیات نصیب ہوں اس لئے مَیں انہیں ترقیات تودوں گا اور بہت بڑی ترقیات دُوں گا لیکن اگر میری نعمتوں کا انہوں نے انکار کیا دین سے نفرت کی.خدا تعالیٰ سے بعد اختیار کیا اور اللہ تعالیٰ کے احکام سے منہ موڑ لیا توفَاِنِّيْۤ اُعَذِّبُهٗ عَذَابًا لَّاۤ اُعَذِّبُهٗۤ اَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِيْنَمَیں عیسائی قوم کو وہ عذاب دُوں گا جو آج تک کبھی کسی قوم کو نہیں دیا گیا.پس چونکہ سورۂ مائدہ میں مسیحی اقوام کو دنیوی ترقیات عطا کرنے کا وعدہ تھا اور پھر اس کے ساتھ ہی یہ خبر تھی کہ اگر انہوں نے کفر کی طرف رجوع کیا تو مَیں اُن پر وہ عذاب نازل کروں گا جو دنیا میں کسی قوم پر نازل نہیں ہوا.اس لئے یہاں کَلَّا کا تکرار اِسی عذاب شدید کی طرف اشارہ کرنے کے لئے کیا گیا ہے کہ اے عیسائیو اب ہوشیار ہو جائو! تم مطفّف بنے ہوئےلوگوں کے حقوق کو غصب کر رہے ہو اوردنیا کی ترقیات کے مزے لُوٹ رہے ہو.میں نے تمہیں کہہ دیا تھا کہ اگر دنیا ملنے کے بعد تم نے نافرمانی کی، میرے اس احسان کو بھلا دیا اور میری طرف سے اپنی توجہ ہٹا کر دنیا پر گر گئے تو پھر میں تمہیںوہ عذاب دُوں گا جو آج تک کسی کو نہیں دیا گیا سو وہ عذاب کی خبر جو میں پہلے سےدے چکا تھا اب اُس کا وقت قریب آرہا ہے اور خدا تعالیٰ کی گرفت تم پر نازل ہونے والی ہے جو نہایت شدید اور ہیبت ناک ہو گی.عیسائیت کی تباہی کے لئے تین جھٹکے پھر کَلَّا کے اس تکرارپر غور کرنے سے ایک اور بات بھی معلوم ہوتی
Page 453
ہے کہ یہاں تین دفعہ کَلَّا کفر کے ذکر کے بعد آتا ہے اور ایک دفعہ کَلَّا مومنوں کے ذکر سے پہلے ہے.اس میں اس طرف بھی اشارہ معلوم ہوتا ہے کہ تین جھٹکے عیسائیت کی تباہی کے لئے لگیں گے اور چوتھا جھٹکا اسلام کے قیام کا موجب ہو گا بظاہر جہاں تک عقل کام دیتی ہے یہی معلوم ہوتا ہے کہ پہلی جنگِ عظیم ۱۹۱۸ء میں ختم ہوئی پہلا جھٹکا تھا جو عیسائیت کو لگا.اب دوسری جنگ جو شروع ہے یہ دوسرا جھٹکا ہے اس کے بعد ایک تیسری جنگ عظیم ہو گی جو مغرب کی تباہی کے لئے تیسرا اور آخری جھٹکا ہو گا.اس کے بعد ایک چوتھا جھٹکا لگے گا جس کے بعد اسلام اپنے عروج کو پہنچ جائے گا اور مغربی اقوام بالکل ذلیل ہو جائیں گی کیونکہ چوتھے کَلَّا کے بعد ہی یہ ذکر آتا ہے کہ اِنَّ كِتٰبَ الْاَبْرَارِ لَفِيْ عِلِّيِّيْنَ.وَ مَاۤ اَدْرٰىكَ مَا عِلِّيُّوْنَ.كِتٰبٌ مَّرْقُوْمٌ.يَّشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُوْنَ۠.خدا تعالیٰ سے محجوب ہونے کا مطلب اِنَّهُمْ عَنْ رَّبِّهِمْ يَوْمَىِٕذٍ لَّمَحْجُوْبُوْنَ میں یَوْمَئِذٍ سے مراد یُکَذِّبُوْنَ بِیَوْمِ الدِّیْنِ والا یوم ہی ہے.فرماتا ہے یہ لوگ اُس دن اپنے رب سے محجوب ہوں گے اس آیت میں رب کا لفظ لاکر اس امر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ربوبیت کا رشتہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسے ماں اور بچہ میں ہوتا ہے.بچے کوماں پالتی ہے، دُودھ پلاتی ہے، اُس کی غوروپرداخت کرتی ہے.اس کی ضروریات کا خیال رکھتی ہے اور اس کو بڑا کرتی ہے.ربؔ کے بھی یہی معنے ہیں کہ وہ انسان کی جسمانی اور روحانی پرورش کے سامان مہیّا کرتا ہے.پس جو رب ہوتا ہے وہ بھی اس شخص کے پاس آنے کی کوشش کرتا ہے جس کی وہ ربوبیت کرتا ہے اور جس کی ربوبیت کی جاتی ہے وہ بھی ربؔ کے پاس آنے کی کوشش کرتا ہے.ماں بھی بچہ سے محبت کرتی ہے اور بچہ بھی ماں سے محبت کرتا ہے پس فرماتا ہے ہمارا اور ان کا رشتہ وہ ہے کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں اور انہیں ہم سے محبت کرنی چاہیے.مگر باوجود اس رشتہ کے اُنہیں گناہوں سے ایسی وابستگی ہو جائے گی کہ یہ اپنے رب سے محجوب ہو جائیں گے.محجوب اس کو کہتے ہیں جو پردہ سے کسی دوسری چیز سے روکا گیا ہو اور جو شخص اپنے رب سے محجوب ہو اُس کی بدقسمتی میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہو سکتا پس فرماتا ہے یہ لوگ کیسے بدقسمت ہیں کہ ربوبیت کے رشتہ کے بعد بھی اپنے رب سے یہ اُس دن محجوب رہیں گے.یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اُس دن محجوب ہونے کے کیا معنے ہیں (۱)کیا باقی انسان خدا تعالیٰ کو دیکھتے ہیں کہ اُن کے متعلق کہا جا ر ہا ہے کہ وہ اپنے رب سے محجوب ہوںگے (۲)دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اُس دن سے پہلے عیسائی خدا تعالیٰ کو دیکھتے تھے کہ فرماتا ہے کہ اُس دن وہ اپنے رب سے محجوب ہوں گے؟ روئیت الٰہی کے درجے اس کا جواب یہ ہے کہ جہاں تک روئیتِ قلب کا تعلق ہے ہر انسان جو بے دین نہ ہو خدا تعالیٰ کو دیکھتا ہے چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَ مَنْ كَانَ فِيْ هٰذِهٖۤ اَعْمٰى فَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ اَعْمٰى
Page 454
(بنی اسرائیل:۷۳) جو شخص اس دنیا میں خدا تعالیٰ کو نہیں دیکھتا وہ آخرت میں بھی اُس کو نہیں دیکھے گا اس سے معلوم ہوا کہ جتنے مومن نجات پانے والے ہیں اُن سب کو خدا تعالیٰ نے اپنا دیکھنے والا قرار دیا ہے مگر دنیا میں ہر مومن یہ نہیں کہتا کہ میں نے خدا تعالیٰ کو دیکھا ہے اس سے معلوم ہوا کہ ایک درجہ رویتِ الٰہی کا محض ایمان لانا ہے.جب کسی شخص کو ایمان نصیب ہو جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اُسے رویت الٰہی نصیب ہو گئی اور ایمان بغیر خد اتعالیٰ کی صفات کا علم رکھنے کے حاصل نہیں ہو سکتا.آخر خدا کسی مادی چیز کا نام تو نہیں بلکہ خدا کا نام ہے اس ہستی کا جو ربّ ہے،جو رحمٰن ہے، جو رحیم ہے اور جو مالک یوم الدین ہے اور اسی طرح اور صفاتِ حسنہ سے متصّف ہے.پس جب کسی نے خدا تعالیٰ کی ربوبیت، اُس کی رحمانیت، اُس کی رحیمیت اور اُس کی مالکیت وغیرہ کو سمجھ لیا اور اس کی دوسری صفات پر یقین رکھا تو اُس کو ایک درجہ روئتِ الٰہی کا نصیب ہو گیا.پس ایک رویت وہ ہے جو ہر مومن کو نصیب ہوتی ہے خواہ وہ ادنیٰ درجے کا مومن ہو یا اعلیٰ درجے کا، اِس میں کوئی استثناء اور امتیاز نہیں ہے.پھر سورۂ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَ مَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِيْ فَاِنَّ لَهٗ مَعِيْشَةً ضَنْكًا وَّ نَحْشُرُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَعْمٰى.قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيْۤ اَعْمٰى وَ قَدْ كُنْتُ بَصِيْرًا.قَالَ كَذٰلِكَ اَتَتْكَ اٰيٰتُنَا فَنَسِيْتَهَا١ۚ وَ كَذٰلِكَ الْيَوْمَ تُنْسٰى(طٰہٰ :۱۲۵ تا ۱۲۷) کہ جو شخص ہمارے ذکر سے اعراض کرتا ہے، ہماری صفات پر غور نہیں کرتا، اُن کا مطالعہ نہیں کرتا، اُس کی زندگی بڑی تنگ زندگی ہوتی ہے.کیونکہ وسعتِ عمل پیدا ہوتی ہے خد اتعالیٰ کی صفات کی وجہ سے جسے خدا تعالیٰ پر سچا ایمان حاصل ہو اُس کے اندر سخاوت ہوتی ہے، سچائی ہوتی ہے، دیانتداری ہوتی ہے، امانت ہوتی ہے، رأفت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے اور وہ اپنے اِن نیک اعمال میںترقی کرتا چلا جاتا ہے مگر جو صفاتِ الٰہیہ پر ایمان نہ رکھتا ہو اُس کا دائرہ عمل نہایت محدود ہوتا ہے.درحقیقت دائرہ عمل اعلیٰ مطمح نظر IDEAL سے وسیع ہوتا ہے جب کوئی اعلیٰ مطمح نظر سامنے نہ ہو تو اعمال محدود ہو جاتے ہیں.یہی وجہ ہے کہ انبیاء کے مقابلہ میں فلاسفروں کے اخلاق بالکل ہیچ ہوتے ہیں اور پھر اُن کے اندر جو تھوڑے بہت اخلاق پائے جاتے ہیں اُن کا دائرہ عمل بھی بہت تنگ ہوتا رسول کریم صلے اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کے اخلاق کو دیکھا جائے یا حضرت موسیٰ علیہ السّلام کے اخلاق کو دیکھا جائے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اخلاق کو دیکھا جائےتو معلوم ہو گا کہ اُن کے اعمال کا دائرہ غیر معمولی طور پر وسیع تھا.اُن کے اندر سچائی بھی شاندار طور پر پائی جاتی تھی، اُن کے اندر امانت بھی شاندار طور پر پائی جاتی تھی، اُن کے اندر سخاوت بھی شاندار طور پر پائی جاتی تھی، اُن کے اندر بشاشت بھی شاندار طور پر پائی جاتی تھی، اُن کے اندر رحم بھی شاندار طور پر پایا جاتا تھا، اُن کے اندر غریبوں کی پرورش کا مادہ بھی شاندار طور پر پایا جاتا تھا، اُن کے اندر انصاف
Page 455
بھی شاندار طور پر پایا جاتا تھا، اُن کے اندر توکّل بھی شاندار طور پر پایا جاتا تھا، غرض بیسیوں قسم کے اخلاق اُن میںنمایاں طور پر نظر آتے ہیں.لیکن اس کے مقابلہ میں اگر تم فلاسفروں کو دیکھو تو ممکن ہے کوئی ایک فلاسفر ایسا نکل آئے جو امین ہو یا جود وسخا کا مادہ اپنے اندر رکھنے والا ہو.لیکن ایک فلاسفر بھی ایسا نہیں نکل سکتا جو سارے اخلاق کا جامع ہو.اس کی وجہ یہی ہے کہ جب تک کوئی اعلیٰ مطمح نظر سامنے نہ ہو.جب تک کوئی ایسی تصویر سامنے نہ ہو جس کی نقل اتاری جا سکے اُس وقت تک اعمال نہایت محدود دائرہ میں چکّر کھاتے رہتے ہیں اور اُن میں وسعت پیدا نہیں ہو سکتی.اور جب کسی کے اعمال نہایت تنگ اور محدود دائرہ کے اندر ہوں تو اُس کے عمل میں وسعت پیدا نہیں ہو سکتی اور جب کسی نے اپنے اعمال میں وسعت ہی پیدا نہیں کی تو وہ قیامت کے دن خدا تعالیٰ کو کس طرح دیکھ سکتا ہے وہ شخص جس نے اپنے آپ کو رب نہیں بنایا وہ اپنے رب خدا کو کس طرح پہچان سکتا ہے.جس نے اپنے آپ کو رحیمؔ نہیں بنایا وہ رحیم خدا کو کس طرح پہچان سکتا ہے.جس نے اپنے آپ کو رحمن نہیں بنایا وہ رحمن خدا کو کس طرح پہچان سکتا ہے.جس نے اپنے آپ کو غفور نہیں بنایا، ستار نہیںبنایا، مہیمن نہیں بنایا، وہ غفور اور ستار اور مہیمن خدا کو کس طرح پہچان سکتا ہے اور وہ قیامت کے دن خدا تعالیٰ کو دیکھنے کی اہلیت ہی کس طرح رکھ سکتا ہے.جس نے خربوزہ نہیں دیکھا وہ خربوزے کو دیکھ کر اُسے پہچان کس طرح کر سکتا ہے وہ تو اُس کی حقیقت معلوم کرنے سے قاصر ہی رہے گا.ایسی صورت میں جب اُس کا دائرہ اعمال نہایت تنگ ہو گا اور خدا تعالیٰ کی صفات کا انعکاس اُس نے اپنے آئینہ قلب میں پیدا نہیں کیا ہو گا تو اس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ قیامت کے دن جب خدا تعالیٰ کی صفات ظاہر ہوں گی وہ اُن کو پہچان نہیں سکے گا بلکہ اندھوں کی طرح کھڑا رہے گا اور اُسے کچھ نظر نہیں آئے گا.جب وہ اندھا ہونے کی حالت میں قیامت کے دن اٹھے گا تو چونکہ وہ اپنے ذہن میں یہ سمجھا کرتا تھا کہ میں بڑا بصیر ہوں، مَیں بڑا فلاسفر اور مدبّر ہوں اس لئے وہ خدا تعالیٰ سے کہے گارَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيْۤ اَعْمٰى وَ قَدْ كُنْتُ بَصِيْرًا.کہ میں تو بڑا بصیر تھا، نفسیات کا علم رکھنے والا تھا، مشاہدات پر اپنے علوم کی بنیاد رکھتا تھا، فلسفہ اور سائنس کا ماہر تھا، کتابوں کا دن رات مطالعہ کیا کرتا تھا، کائناتِ عالم کے اسرار پر غور کیا کرتا تھامجھے آج اندھا کیوں پیدا کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا كَذٰلِكَ اَتَتْكَ اٰيٰتُنَا فَنَسِيْتَهَا١ۚ وَ كَذٰلِكَ الْيَوْمَ تُنْسٰى تیرے سامنے اپنے نبی کے ذریعہ ہم نے نشانات و معجزات ظاہر کئے، ہم نے اپنے قادرؔ ہونے کے نشانات ظاہر کئے، اپنے رب ہونے کے ثبوت دئے، اپنے رحیم ہونے کے دلائل دئے، اپنے مالک ہونے کے شواہد مہیّا کئے، اپنے مُحی اور ممیت ہونے کےثبوت پیش کئے مگر تُو نے اُن کی طرف توجہ نہ کی.تُو ہمارے نبی کو دیکھ کر یہی کہتا رہا کہ یہ لغو باتیں ہیں ایک مُلّا اِن باتوں کو کیا جانے، میں فلاسفر ہوں، میں کینٹؔ اور میں ہیگل ہوں، میں
Page 456
ایسے لغو امور کی طرف توجہ کر کے اپنے وقت کو ضائع کرنا نہیں چاہتا.جب تُو نے ہماری طرف توجہ نہ کی تو ہم نے بھی تیری طرف توجہ نہ کی آنکھیں چونکہ ہماری طرف سے ملتی ہیں اور وہ نور بھی ہم ہی دیتے ہیں جس سے انسان دیکھ سکتا ہے اس لئے یہ چیزیں تجھے اسی صورت میں مل سکتی تھیں جب تو ہماری طرف توجہ کرتا.جب تُو نے ہم سے منہ پھیر لیا تو ہم نے بھی اپنا نورتجھ سے واپس لے لیا اَور تُو اِس جہان میں اندھا پیدا ہوا.اس سے معلوم ہوتا ہے کہ معجزات و نشانات سے مومن کو ایک رویت نصیب ہوتی ہے جو اس سے محروم ہو وہ اس سے بڑی رویت سے بھی جو دنیا یا آخرت میں ہو گی محجوب ہوں گے.دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا وہ اُس دن سے پہلے خدا تعالیٰ کو دیکھتے تھے کہ اُن کے متعلق فرمایا گیا ہے اِنَّهُمْ عَنْ رَّبِّهِمْ يَوْمَىِٕذٍ لَّمَحْجُوْبُوْنَ اُس دن وہ خدا تعالیٰ سے محجوب ہوں گے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس دن محجوب ہونے کے یہ معنے ہیں کہ وہ تو رویت کا دن مقرر ہے اُس دن بھی انہیں رویت نصیب نہ ہو گی.یعنی عام قاعدہ یہ ہے کہ علم کے ساتھ چیز کی شناخت ہوتی ہے لیکن بعض دفعہ دل پر ایسا زنگ لگا ہوا ہوتا ہے کہ علم کے ساتھ عرفان نہیںآتا دنیا میں عام قانون یہ ہے کہ علم کے ساتھ ہی عرفان آجاتاہے کسی کو کہہ دیں کہ یہ افیون ہے تو وہ اُس کے کھانے سے احتراز کرے گااور سمجھے گا کہ اگر میں نے افیون کھائی تو میں بیمار ہو جائوں گا یا میرے اعصاب کمزور ہو جائیں گے اس لئے وہ افیون کھانے سے ڈرتا ہے مگر ایک اور شخص ہوتا ہے جسے افیون کھانے کی عادت ہو چکی ہوتی ہے اُسے خواہ ڈاکٹر منع کریں، خواہ اس کے اخلاق خراب ہوں، خواہ اُس کی صحت برباد ہو اُس پر کوئی اثر ہوتا ہی نہیں اور وہ برابر افیون استعمال کرتا چلا جاتا ہے.گویا اُسے علم تو ہوتا ہے مگر عرفان نہیں ہوتا پُرانی عادت اور دل کے زنگ کی وجہ سے علم کے باوجود اسے معرفت حاصل نہیں ہوتی اور وہ افیون کا استعمال ترک نہیں کر سکتا.تو یہ دو حالتیں ہیں جو مختلف انسانوں پر وارد ہوتی ہیں.رویت درحقیقت عرفان کا نام ہے علم کا نام نہیں.وہ دن چونکہ رویت کے لئے مقرر ہو گا اور رویت عرفان سے حاصل ہوتی ہے نہ کہ علم سے.اس لئے باوجود اس علم کے کہ وہ غلطی میں مبتلا تھے جب خدا تعالیٰ کی قدرتیں اور اُس کی طاقتیں ظاہر ہوں گی تو اُن کو عرفان حاصل نہیں ہو گا کیونکہ اُن کے دل گندے ہو چکے ہوں گے.گویا عرفان جو علم کا ایک طبعی نتیجہ ہے وہ ساتھ نہیں آئے گا جیسے افیون کھانیوالے کو خواہ کتنا ڈرائو وہ اُسے چھوڑ نہیں سکتا کیونکہ اسے افیون کھانے کی عادت پڑ چکی ہوتی ہے.فرماتا ہے چونکہ وہ دن انکشاف کا ہو گا اُنہیں علم تو حاصل ہو جائے گا مگر چونکہ اُن کے قلوب گندے ہو چکے ہوں گے اس لئے علم کے باوجود اُنہیں عرفان حاصل نہ ہو گا وہ کہیں گے کہ خدا قادر ہے، وہ سمجھیں گے کہ خدا رحیمؔ ہے، وہ سمجھیں گے کہ خدا عزیز ہے مگر باوجود اس کے اپنے ربؔ اور
Page 457
رحیمؔ اور قادر اور کریم خدا سے اُن کا کوئی تعلق نہیں ہو گا اور اس وجہ سے وہ جنّت کے مستحق نہیں ہوں گے بلکہ دوزخ کے ہی مستحق رہیں گے.كَلَّاۤ اِنَّ كِتٰبَ الْاَبْرَارِ لَفِيْ عِلِّيِّيْنَؕ۰۰۱۹ یُوں نہیں (جس طرح تم کہتے ہو بلکہ) ابرار (کی جزاء) کا حکم یقیناً عِلّیّین میں ہے.تفسیر.فرماتا ہے خبردار! تم یہ سمجھتے ہو کہ مومن ترقی نہیں کریں گے! یہ بالکل غلط ہے مومنوں کی قسمت توعلّیّین میں لکھی ہوئی ہے.اگر اس کے معنے قرآن کریم کے کئے جائیں تو علّیّین سے مراد قرآن کریم کے وہ حصّے ہوں گے جن میں مومنوں کی ترقیات کے متعلق اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیشگوئیاں موجود ہیں.اور اگر علّیّین سے مراد اعلیٰ مقامات لے لو تو اس کے معنے یہ ہوں گے کہ مومنوں کی قسمت تو اعلیٰ درجہ کے مقامات کے متعلق فیصل شدہ ہے.علّیّین کے متعلق حضرت ابن عباس کاایک قول علّیّین کے متعلق حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ اس سے مراد جنّت ہے (ابن کثیرزیر آیت ھذا) اور مفردات والے لکھتے ہیں کہ بَلْ ذالِکَ فِی الْحَقِیْقَۃِ اِسْمُ سُکَّانِھَا درحقیقت یہ جنت میں رہنے والوں کا نام ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ھٰذَا اَقْرَبُ فِی الْعَربِیَّۃِ اِذْ کَانَ ھٰذَا الْجَمْعُ یَخْتَصُّ بِالنَّاطِقِیْنَ.عربی زبان کے لحاظ سے علّیّین کے یہ معنے بالکل درست ہیں کیونکہ یہ جمع ذوی العقول کے ساتھ ہی مختص ہے.پس اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِیْ عِلِّیِّیْنَ کے یہ معنے ہوئے کہ ابرار کا نام علّیّین میںلکھا ہوا ہے یا جہاں علّیّین کا ذکر ہے وہاں اِن کا بھی ہے.ابن ماجہ.طبرانی اور بیہقی میں عبداللہ بن کعب بن مالک کی ایک روایت آتی ہے جس سے پتہ لگتا ہے کہ علّیّین کیا چیز ہے حضرت عبداللہ ؓ کہتے ہیں کہ لَمَّا حَضْرَتْ کَعْبًا الْوَفَاۃُ اَتَتْہُ اُمُّ بِشْرٍ بِنْتُ الْبَرَاءِ فَقَالَتْ اِنْ لَّقِیْتَ اِبْنِیْ فَاَقْرَئْ ہُ مِنِّی السَّلامَ فَقَالَ غَفَرَ اللّٰہُ لَکَ اُمَّ بِشْرٍ نَحْنُ اَشْغَلُ مِنْ ذَالِکَ فَقَالَتْ اَمَا سَمِعْتَ رَسُوْلَ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہِ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ یَقُوْلُ اِنَّ نَسَمَۃَ الْمُؤْمِنِ تَسْرَحُ فِی الْجَنَّۃِ حَیْثُ شَآءَ تْ وَاِنَّ نَسَمَۃَ الْکَافِرِ فِیْ سِجِّیْنٍ قَالَ بَلٰی قَالَتْ فَھُوَ ذَالِکَ.یعنی عبداللہ بن کعب بن مالک کہتے ہیں جب حضرت کعبؓ کی وفات قریب پہنچی تو ایک صحابیہ اُمّ بشر نام اُن کے پاس آئیں اور جب اُنہوں نے اُن کو حالتِ نزع میں دیکھا تو وہ کہنے لگیں میاں کعب تمہیں اگلے جہان میں اگر میرابیٹا نظر آ جائے تو اُسے میرا سلام کہہ دینا.حضرت کعبؓ کہنے لگے غَفَرَ اللّٰہُ لَکَ اُمَّ بِشْرٍ.اے اُمِّ بشر اللہ تعالیٰ تجھے معاف کرے.میری جان کندنی کا وقت ہے
Page 458
علّیّین کے متعلق حضرت ابن عباس کاایک قول علّیّین کے متعلق حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ اس سے مراد جنّت ہے (ابن کثیرزیر آیت ھذا) اور مفردات والے لکھتے ہیں کہ بَلْ ذالِکَ فِی الْحَقِیْقَۃِ اِسْمُ سُکَّانِھَا درحقیقت یہ جنت میں رہنے والوں کا نام ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ھٰذَا اَقْرَبُ فِی الْعَربِیَّۃِ اِذْ کَانَ ھٰذَا الْجَمْعُ یَخْتَصُّ بِالنَّاطِقِیْنَ.عربی زبان کے لحاظ سے علّیّین کے یہ معنے بالکل درست ہیں کیونکہ یہ جمع ذوی العقول کے ساتھ ہی مختص ہے.پس اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِیْ عِلِّیِّیْنَ کے یہ معنے ہوئے کہ ابرار کا نام علّیّین میںلکھا ہوا ہے یا جہاں علّیّین کا ذکر ہے وہاں اِن کا بھی ہے.ابن ماجہ.طبرانی اور بیہقی میں عبداللہ بن کعب بن مالک کی ایک روایت آتی ہے جس سے پتہ لگتا ہے کہ علّیّین کیا چیز ہے حضرت عبداللہ ؓ کہتے ہیں کہ لَمَّا حَضْرَتْ کَعْبًا الْوَفَاۃُ اَتَتْہُ اُمُّ بِشْرٍ بِنْتُ الْبَرَاءِ فَقَالَتْ اِنْ لَّقِیْتَ اِبْنِیْ فَاَقْرَئْ ہُ مِنِّی السَّلامَ فَقَالَ غَفَرَ اللّٰہُ لَکَ اُمَّ بِشْرٍ نَحْنُ اَشْغَلُ مِنْ ذَالِکَ فَقَالَتْ اَمَا سَمِعْتَ رَسُوْلَ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہِ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ یَقُوْلُ اِنَّ نَسَمَۃَ الْمُؤْمِنِ تَسْرَحُ فِی الْجَنَّۃِ حَیْثُ شَآءَ تْ وَاِنَّ نَسَمَۃَ الْکَافِرِ فِیْ سِجِّیْنٍ قَالَ بَلٰی قَالَتْ فَھُوَ ذَالِکَ.یعنی عبداللہ بن کعب بن مالک کہتے ہیں جب حضرت کعبؓ کی وفات قریب پہنچی تو ایک صحابیہ اُمّ بشر نام اُن کے پاس آئیں اور جب اُنہوں نے اُن کو حالتِ نزع میں دیکھا تو وہ کہنے لگیں میاں کعب تمہیں اگلے جہان میں اگر میرابیٹا نظر آ جائے تو اُسے میرا سلام کہہ دینا.حضرت کعبؓ کہنے لگے غَفَرَ اللّٰہُ لَکَ اُمَّ بِشْرٍ.اے اُمِّ بشر اللہ تعالیٰ تجھے معاف کرے.میری جان کندنی کا وقت ہے اور تُواپنے بیٹے کاسلام مجھے پہنچا رہی ہے مجھے تو اس وقت یہ فکر ہے کہ میں نے خدا کو کیا جواب دینا ہے تیرے بیٹے کو سلام پہنچانا کس کو یاد رہے گا.وہ کہنے لگیں کیا تم نے رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم سے یہ بات نہیں سنی کہ مومن کی روح جنّت میں جہاں چاہتی ہے چلی جاتی ہے لیکن کافر کی رُوح سجّین میں پڑی رہتی ہے؟ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ علّیّین کے معنے آزادی اور حُرّیت کے ہیں کیونکہ بتایا گیا ہے کہ اِنَّ نَسَمَۃَ الْمُؤْمِنِ تَسْرَحُ فِی الْجَنَّۃِ حَیْثُ شَآءَ تْ مومن کی روح جنت میں جہاں چاہے گی جا سکے گی.اس کے مقابلہ میں سجّین کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اور سجّین کے معنے مَیں اس سے پہلے بتا چکا ہوں کہ قید کے ہیں.پس علّیّین کے معنے آزادی اور حُرّیت کے ہوئے اور آیت کا مطلب یہ ہوا کہ کفّار نے جس طرح اپنے اعمال کا دائرہ بہت محدود رکھا تھا اور جس طرح اعمال صالحہ کی بجا آوری میں انہوں نے کوتاہی کی تھی اسی طرح اُنہیں سجّین یعنی ایک قید کی حالت میں رکھا جائے گا لیکن مومن نے چونکہ اپنے اعمال کا دائرہ غیر معمولی طور پر وسیع رکھا تھا اس لئے وہ علّیّین میں شامل ہو گا یعنی ایسی جماعت میں جس کی نیکی اور اتقاء کی کوئی حد ہی نہیں.یہ معنے تو دنیا کے لحاظ سے ہیں.لیکن آخرت کے لحاظ سے اس کے یہ معنے ہوں گے کہ جس طرح اس جہان میں اُس نے اپنے اعمال کا دائرہ وسیع کر رکھا تھا اسی طرح اگلے جہان میں خدا اس سے یہ سلوک کرے گا کہ وہ اس کی روح کو آزاد رکھے گا اور وہ جہاں چاہے گا جا سکے گا.میں نے اپنی کتاب ’’احمدیت یعنی حقیقی اسلام‘‘ میں اس امر پر بحث کی ہے کہ روحِ انسانی جنت میں ہر جگہ جا سکتی ہے مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ سب جنّتیوں کا ایک درجہ ہو جائے گا.میں نے وہاں ثابت کیا ہے کہ ایک جنتی ہر جگہ جا بھی سکتا ہے اور درجوں میں بھی فرق رہ سکتا ہے.(انوار العلوم جلد ۸ ’’احمدیت یعنی حقیقی اسلام صفحہ ۳۳۶).الغرض اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ كِتٰبَ الْاَبْرَارِ لَفِيْ عِلِّيِّيْنَ اے عیسائیو! یاد رکھو کہ تمہاری تباہی کے لئے تین زبردست جھٹکے لگیں گے اور تباہی کے ان تینوں دَوروں کے بعد جب آخری جھٹکا لگے گا تو یکدم مسلمانوں کونیچے سے اُٹھا کر اعلیٰ درجہ کے مراتب پر پہنچا دیا جائے گا.
Page 459
وَ مَاۤ اَدْرٰىكَ مَا عِلِّيُّوْنَؕ۰۰۲۰كِتٰبٌ مَّرْقُوْمٌۙ۰۰۲۱ اور تجھے کس نے بتایا ہے کہ علّیّون کیا ہے.ایک لکھا ہوا حکم ہے جسے مقرب لوگ يَّشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُوْنَ۠ۙ۰۰۲۲ (خود اپنی آنکھوں سے) دیکھیں گے.تفسیر.فرماتا ہے.اے سننے والے! تجھے کیا پتہ کہ عِلِّیُّوْن کس کو کہتے ہیں کِتَابٌ مَّرْقُوْمٌ یہ ایک دفتر ہے جو لکھا ہوا ہے یا کِتَابٌ مَخْتُوْمٌ ایک ایسا فیصلہ ہے جس پر مہر لگ چکی ہے اور جو اٹل ہے یا یہ کہ یہ ایک لکھا ہوا فیصلہ ہے اس کے بھی وہی معنے ہیں جو پہلے کے ہیں کیونکہ اٹل اُسی فیصلہ کو کہتے ہیں جو لکھا ہوا ہو.يَّشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُوْنَ۠.یہ نتیجہ یا یہ انجام جس کا اُوپر ذکر کیا گیا ہے اس کو مقرّب لوگ دیکھیں گے یا حاضر ہوںگے اس مقام پر مقرب.یہ فرق ہے جو مومن اور کافر میں ہےیعنی کافر کے لئے وہ دن ایسا ہو گا کہ وَيْلٌ يَّوْمَىِٕذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ.وہ آہیں بھرے گا.افسوس کرے گا اور کوشش کرے گا کہ کِسی طرح میں اس انجام سے بھاگوں لیکن مقرب اس کی طرف دوڑ کر جائے گا اور اپنی مرضی سے جائے گا کیونکہ اس کےلحاظ سے وہ پسندیدہ انجام ہو گا.گویا کفّار کی تباہی اور اس کے مقابلہ میں مومنوں کے اقتدار کی پیشگوئی یہاں آکر ختم کی اور بتایا کہ بے شک مطفّفین کا ایک لمبے عرصہ تک غلبہ چلا جائے گا مگر اللہ تعالیٰ اس غلبہ کو ضرور ختم کرے گا.عیسائیت کی تباہی کے بعد اسلام کے غلبہ کے لئے ایک جھٹکا چنانچہ ایک ہی سورۃ میں چار دفعہ تھوڑے تھوڑے وقفہ کے بعد کَلَّا کے استعمال میں یہ مخفی اشارہ پایا جاتا ہے کہ مغربی اقوام کی تباہی کے لئے تین زبردست جھٹکے لگیں گے اس کے بعد چوتھا جھٹکا ایسا ہو گا جو اِن مطفّفین کا انجام اُن کی آنکھوں کے سامنے لے آئے گا.اسلام غالب آ جائے گا.کفر تباہ ہو جائے گا اور ان عیسائیوں کا انجام ایسا خطرناک ہو گا کہ وہ اِس سے بھاگنے کی پوری کوشش کریں گے مگر وہ اس سے بھاگ نہیں سکیں گے لیکن مومن اپنے انجام کی طرف دوڑ کر جائیں گے اور کہیں گے کہ یہ کیسا اچھا انجام ہے.کفار کے لئے لفظ سجین مفرد لانے اور مومنوں کے لئے علیون جمع استعمال کرنے میں
Page 460
حکمت یہ نکتہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ سجّین کا لفظ جو کفّار کے لئے استعمال ہوا تھا مفرد تھا مگر عِلِّیِّین کا لفظ جو مومنوں کے لئے استعمال ہوا ہے وہ جمع کا لفظ ہے اس فرق سے اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ کافر کی سزا کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا نہیں مگر مومن کے انعام کو بڑھاتا چلا جاتا ہے جس کی وجہ سے کافر تو ایک ہی قید خانہ میں پڑا رہتا ہے لیکن مومن گھر بدلتا جاتا ہے ایک گھر کے بعد اُس سے اعلیٰ گھر اُسے ملتا ہے اور اس کے بعد اس سے اعلیٰ گھر.اسی طرح خدا تعالیٰ اُسے کئی دنیائوں کی سیر کرا دیتا ہے اس لئے مومن کے گھر کئی ہوں گے اور کافر کا گھر ایک.پس کافر کے گھر کے لئے مفرد لفظ استعمال ہوا او ر مومن کے لئے چونکہ کئی گھر ہونے تھے اس کے بارہ میں جمع کا لفظ استعمال کیا.اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِيْ نَعِيْمٍۙ۰۰۲۳ نیکی میںبڑھے ہوئے لوگ یقیناً نعمت (کے مقام) میں رکھے جائیںگے.حَلّ لُغَات.نَعِیْم نَعِیْم کے لئے دیکھو سورہ انفطار آیت نمبر ۱۴.تفسیر.یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ نعمت اُن پر ہو گی بلکہ یہ فرمایا کہ وہ نعمت میں ہوں گے.اس سے مراد یہ ہے کہ تمام ماحول کو اُن کے لئے نعمت بنا دیا جائے گا.کسی چیز کو کسی انسان پر گرایا جائے تو وہ گِر کر پھیل جاتی ہے.اس کی یُوں مثال سمجھ لو کہ ایک شخص پر پانی کا لوٹا گرایا جائے اور ایک شخص ایسا ہو جو تالاب میں کود جائے.پانی کو تو یہ دونوں چھوئیں گے مگر پانی سے اُس کا تعلق جس پر ایک لوٹا گرایا گیا ہے اور اس کا جو تالاب میں کُودا ہے ایک نمایاں فرق رکھتا ہو گا.پس اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِیْ نَعِیْمٍ کا یہ مطلب ہے کہ اُن کے لئے تمام ماحول نعمت کا بنا دیا جائے اور وہ ایسا ہی ہو گا جیسے کوئی تالاب میں کود جاتا ہے گویا خدا تعالیٰ کی نعمت ان کو چاروں طرف سے ڈھانپ لے گی.عَلَى الْاَرَآىِٕكِ يَنْظُرُوْنَۙ۰۰۲۴ چھپر کھٹوں پر (بیٹھے سب حال) دیکھ رہے ہوں گے.حَلّ لُغَات.اَرَآئِکَ:اَرَآئِکُ اَرِیْکَۃٌ کی جمع ہے اور اس کے معنے ہوتے ہیں سَرِیْرٌ مُنَجَّدٌ مُزَیَّنٌ فِیْ قُبَّۃٍ اَوْ بَیْتٍ فَاِذَا لَمْ یَکُنْ فِیْہِ سَـرِیْرٌ فَھُوَ حَجْلَۃٌ (اقرب).ایک ایسا تخت جو مزین ہو.نقش ونگار والا ہو.سونے کا کام اُس پر کیا گیا ہو.اور اُس کو ایک قُبّہ یا ایک کمرہ میں رکھا گیا ہو.مطلب یہ کہ اسے پردہ دار بنایا گیا ہو
Page 461
جب جی چاہے پردے ڈالے جا سکیں اُردو میں اسے چھپرکھٹ کہتے ہیں.تفسیر.یَنْظُرُوْنَ اَبْرَار کی صفت ہے کہ اَبْرَار اُس وقت دیکھتے ہوں گے یا یہ اُس کا حال ہے اور مطلب یہ ہے کہ بعض نعماء دنیا میں ملتی ہیں مگر انسان اُن کی حقیقت کو سمجھتا نہیں.جب اللہ تعالیٰ مومنوں کو یہ نعمت دے گا تو اُن کی حالت ایسی ہو گی کہ وہ دیکھ رہے ہوں گے یعنی وہ سمجھتے ہوں گے کہ اس نعمت کی کیا قدر و قیمت ہے.اس کی موٹی مثال یہ دیکھ لو کہ اگر ایک بچے کو ہیرا دے دو تو وہ ہر گز یہ خیال نہیں کرے گا کہ اُسے کوئی قیمتی چیز دے دی گئی ہے.اسی طرح بعض قوموں کو دنیوی نعمتیں مل جائیں تو وہ اُن کی حقیقت کو نہیں سمجھتیں جیسے یورپ والوں کو مائدہ ملا اور وہ مائدہ ملا جس کے لئے حضرت عیسٰی علیہ السّلام نے دعا کی تھی مگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اُنہیں جو کچھ حاصل ہوا اپنے زورِ بازو سے حاصل ہوا ہے گویا دیکھنے والی نظر ماری گئی ہے.عَلَى الْاَرَآىِٕكِ يَنْظُرُوْنَکا مطلب لیکن مومنوں کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ہم اُنہیں نعمتیں دیں گے تو ایسی حالت میں دیں گے کہ عَلَى الْاَرَآىِٕكِ يَنْظُرُوْنَ وہ آرائک پر بیٹھے ہوئے خوب سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ نعمتیں اُنہیں اُن پیشگوئیوں کی وجہ سے ملی ہیں جو اُن کے متعلق کی گئی تھیں.گویا بصیرتِ روحانی اُن کے اندر موجود ہو گی.اس لئے بارِ امانت کو وہ صحیح طور پر اٹھائیں گے.چنانچہ حضرت ابو بکرؓ کو دیکھ لو.حضرت عمرؓ کو دیکھ لو.حضرت عثمانؓ اور حضرت علیؓ کو دیکھ لو.انہوں نے ایک ایک قدم پر یہ سمجھا کہ یہ چیز ہماری نہیں بلکہ خدا تعالیٰ نے ہم کو دی ہے اور جب انہوں نے اس بات کو سمجھا تو انہوں نے اس چیز کی اسی طرح حفاظت کی جس طرح خدا تعالیٰ کی چیز کی حفاظت کی جانی چاہیے.یَنْظُرُوْنَ کو اگر ابرار کی صفت سمجھا جائے تو اس صورت میں مفسّرین یہ لکھتے ہیں کہ اس آیت کے معنے یہ ہیں کہ (۱)اعلیٰ نظّارے مومنوں کے سامنے کئے جائیں گے یعنی دیکھنے کی عمدہ عمدہ چیزیں اُن کے سامنے ہوں گی (۲)دوسرے یہ کہ وہ کفّار کا عذاب دیکھیں گے.(روح المعانی زیر آیت ھٰذا) درحقیقت مفسّرین کے سامنے یہی بات رہی ہے کہ وُہ اِن آیات کو قیامت کے متعلق مخصوص سمجھتے ہیں اور چونکہ وہ ان آیات کو قیامت کے متعلق سمجھتے ہیں اس لئے اسی ماحول کی چیزیں اُن کے ذہن میں آتی ہیں.لیکن ہمارے نزدیک گو یہ آیتیں قیامت پر بھی چسپاں ہو سکتی ہیں مگر قیامت کے آنے سے پہلے اس دنیا کی بھی نعمتیں مراد ہیں جن کے دئے جانے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابرار کو وعدہ ہے اس لئے میرے نزدیک اوّلؔ تو یہ جواب ہے پہلی چیز کا پہلے اللہ تعالیٰ نے کفار کے متعلق فرمایا تھا كَلَّاۤ اِنَّهُمْ عَنْ رَّبِّهِمْ يَوْمَىِٕذٍ لَّمَحْجُوْبُوْنَ خبردار ہو جائو اور سُنو! کہ
Page 462
اُس دن کافر اپنے رب سے محجوب ہوں گے یعنی اپنے رب کی شکل اُن کو نظر نہیں آئے گی.جب فجّار کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا تھا کہ اِنَّهُمْ عَنْ رَّبِّهِمْ يَوْمَىِٕذٍ لَّمَحْجُوْبُوْنَ تو ضروری تھا کہ اس کے بعد ابرار کا ذکر کر کے بتایا جاتا کہ اُن کا کیا حال ہو گا.سو اس کے مقابلہ میں فرما دیا کہ اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِيْ نَعِيْمٍ.عَلَى الْاَرَآىِٕكِ اِلٰی رَبِّھِمْ يَنْظُرُوْنَ پس یَنْظُرُوْنَ سے مراد وہی چیز لی جائے گی جس کے متعلق پہلی آیات میں قرینہ موجود ہے اسی وجہ سے جس چیز کو دیکھنا ہے اُس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر نہیں کیا اور مراد یہ ہے کہ اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِيْ نَعِيْمٍ.عَلَى الْاَرَآىِٕكِ اِلَی رَبِّھِمْ يَنْظُرُوْنَ پس یَنْظُرُوْنَ کے ایک معنے یہ ہیں کہ مومن اپنے رب کو دیکھیںگے.محجوب نہیں ہوں گے.یہ دیکھنا دو طرح ہوتا ہے.ایک صفاتی نظری یعنی صفاتِ الٰہیہ کا ظہور بیرونی دنیا میں.جیسے ہمارے ملک میں کہتے ہیں کہ خدا یاد آگیا.جب کوئی بڑی مصیبت ظاہر ہو یا کوئی بڑا تغیّر رونما ہو یا ایسے حالات پیدا ہوں جو غیر معمولی ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ خدا یاد آگیا.یہ بھی محاورہ ہے کہ خدا نظر آگیا.پس اِلَی رَبِّھِمْ یَنْظُرُوْنَ کے ایک معنے یہ ہوئے کہ جب وقت آئے گا تو ایسے عظیم الشان تغیّرات خدا تعالیٰ پیدا کر دے گا کہ جس شخص کے اندر ذرا بھی ایمان ہو گا وہ کہے گا کہ یہ تغیّر خدا تعالیٰ کے سوا اور کسی نے نہیں کیا.اس کی مثال موجود ہے.حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ کے والد مکّہ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ مدینہ سے ایک شخص وہاں جا نکلا.انہوں نے اُس سے کہا کہ سنائو مدینہ کا کیا حال ہے؟ـ اُس نے جواب میں کہا کہ رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں.حضرت ابو بکرؓ کے والد نے پوچھا پھر کیا ہوا؟ اُس نے کہا لوگوں نے ایک شخص کو خلیفہ منتخب کر لیا ہے.انہوں نے پوچھا کس کو؟ اُس نے جواب دیا ابوبکر کو.اس پر انہوں نے پوچھا کون ابوبکر؟ اُس نے جواب دیا ابن ابی قحافہ.اس پر انہوں نے مختلف خاندانوں کا نام لیا کہ فلاں فلاں بڑے خاندانوں کے لوگوں نے مان لیا؟ اُس نے کہا ان قبائل نے بھی بیعت کر لی ہے.جب یہ ساری بات ہو گئی تو حضرت ابو بکرؓ کے والد بے اختیار کہہ اٹھے اَشْھَدُ اَنْ لَآاِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ وَحْدَہٗ لَا شَرِیْکَ لَہٗ وَاَشْھَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُہٗ وَرَسُوْلُہٗ.(الطبقات الکبریٰ ذکر بیعۃ ابی بکر ) میں گواہی دیتا ہوں کہ واقعہ میں خدا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلے اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں.یعنی اگر یہ بات نہ ہوتی تو مکّہ کے لوگ جو دوسرے کی اطاعت نہیں کر سکتے تھے.جو کسی کی بات تک نہیں مانتے تھے اور پھر بڑے بڑے قبائل اور خاندانوں کے لوگ ابو بکرؓ کو کس طرح اپنا خلیفہ مان لیتے.اسی طرح انصار اپنے شہر میں رہتے تھے اور ایسی حالت میں ان کو خیال پیدا ہو سکتا تھا کہ حکومت ہمارے ہاتھ میں آنی چاہیے مگر مدینہ میں بیٹھے ہوئے انہوں نے مکہ کے ایک شخص ابوبکرؓ کے ہاتھ پر بیعت کر لی.تو فرماتا ہے ایسے حالات پیدا ہوں گے کہ لوگ کہیں گے ہمیں خدا نظر آگیا جس طرح ابو قحافہ کو ابو بکرؓ کی خلافت پر خدا
Page 463
یاد آ گیا اور اُس نے کہا اَشْھَدُ اَنْ لَآاِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ وَحْدَہٗ لَا شَرِیْکَ لَہٗ وَاَشْھَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُہٗ وَرَسُوْلُہٗ.دوسرا دیکھنا ایسا ہوتا ہے جیسے روحانی طور پر اللہ تعالیٰ بندے کے قلب پر اپنے آپ کو نازل کر کے یقین کامل کا مقام پیدا کر دیتا ہے.مگر یہ دیکھنا پہلے دیکھنے کے بعد ہوتا ہے کیونکہ قلبی روئت میں بعض دفعہ شبہ پیدا ہو اجاتا ہے کہ وہ خیالی یا وہمی تو نہیں.اس لئے جب اللہ تعالیٰ ارد گرد نشانات دکھا لیتا ہے تو پھر انسانی قلب پر نازل ہوتا ہے اور چونکہ ایسا شخص پہلے صفات الٰہیہ کو اپنے اردگرد دیکھ چکا ہوتا ہے اس لئے جب یہ ظہور اس کے سامنے آتا ہے تو اُسے اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق یقین کامل پیدا ہو جاتا ہے.چنانچہ اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بھی بیان فرمایا ہے کہ وَفِی الْاَرْضِ اٰیَاتٌ لِّلْمُوْقِنِیْنَ وَفِیْ اَنْفُسِکُمْ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ (الزاریات:۲۱،۲۲) یہاں پہلے فِیْ الْاَرْضِ اٰیٰتٌ فرمایا ہے اور پھر وَ فِیْ اَنْفُسِکُمْ کو بیان فرمایا ہے پس اللہ تعالیٰ کی یہی سنّت ہے کہ وہ پہلے اردگرد نشانات دکھاتا ہے اور پھر انسانی قلب پر اپنی تجلّی نازل کرتا ہے تا کہ وہ دھوکا میں نہ رہے.رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہافرماتی ہیں کہ آپ پر وحی کا ابتداء رویاء صالحہ سے ہوا جو فلق الصبح کی طرح پوری ہوتی تھیں (صحیح بخاری کتاب بدء الوحی باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ).اس قسم کے حالات اللہ تعالیٰ خود ہی پیدا کرتا ہے تا کہ وحی و الہام کا مورد بھی کوئی شُبہ نہ کرے اور لوگ بھی یہ نہ کہیں کہ یہ پاگل ہو گیا اس کے بعد قلب پر تجلّی نازل ہوتی ہے.حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام پر اللہ تعالیٰ کی جو تجلّیا ت ہوئیں اُن میں بھی اسی تدریج کا پہلو نظر آتا ہے.پہلے اس قسم کے الہامات نازل ہونے شروع ہوئے کہ ’’ آج حاجی ارباب محمد لشکر خاں کے قرابتی کا روپیہ آتا ہے‘‘ (براہین احمدیہ روحانی خزائن جلد ۱ صفحہ ۲۶۵) یا ’’ڈگری ہو گئی ہے مسلمان ہے‘‘ (براہین احمدیہ روحانی خزائن جلد ۱ صفحہ ۶۵۹) اور جب تواتر کے ساتھ اِن الہامات نے پورا ہو کر ادھر لوگوں کو آپ کی سچائی کی طرف متوجہ کر دیا اور اُدھر آپ کے دل میں یقین پیدا ہو گیا تو اس کے بعد آخری تجلّی ہوئی.غرض اللہ تعالیٰ پہلے سے ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ دُور بین نگاہ رکھنے والا سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ پردۂ قدرت سے اب کچھ ظاہر ہونے والا ہے.پس عَلَى الْاَرَآىِٕكِ يَنْظُرُوْنَ کے یہ معنے ہوئے کہ جو ادنیٰ مومن ہیں وہ خدا تعالیٰ کی اس تجلّی کو دیکھیں گے جو اردگرد ہوتی ہے اور جو کامل مومن ہیں وہ خدا تعالیٰ کی اُس تجلی کو دیکھیں گے جو اُن کے اپنے نفس میں ظاہر ہو گی.عَلَى الْاَرَآىِٕكِ يَنْظُرُوْنَمیں صحابہ کے خصائص کی طرف اشارہ یہ تو پہلے معنوں کے الف اور باء دو حصے تھے مگر اس کے ایک اور معنے بھی ہیں اور وہ یہ کہ یَنْظُرُوْنَ کے لفظ سے اس طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ آرائک اور سُرُر تو سونے کا مقام ہوتے ہیں.انسان اُن پر لیٹتا ہے اس لئے کہ وہ آرام کرے یا اس لئے کہ وہ سو کر اپنی کوفت کو
Page 464
دُور کرے.لیکن فرماتا ہے وہ ایسے دیندار لوگ ہوں گے کہ ایسے مقامات پر بھی کہ سونے اور آرام کرنے کے ہیں چُست اور ہوشیار ہوں گے اور اپنے مفوضہ کاموں کی کڑی نگرانی رکھیں گے گویا بتایا کہ اَور لوگوں کی یہ حالت ہوتی ہے کہ جب انہیں نعمتیں ملتی ہیں.آرام و آسائش کے سامان حاصل ہوتے ہیں تو وہ سُست اور غافل ہو جاتے ہیں.اپنے فرائض کو عمدگی سے ادا نہیں کرتے.لوگوں کے حقوق کو ادا کرنے کا فکر نہیں کرتے.وہ دنیوی عیش کے سامانوں میں اس قدر منہمک ہو جاتے ہیں کہ تمام فرائض کو بھلا بیٹھتے ہیں مگر ابرار کی یہ حالت نہیں ہو گی.جب اللہ کی طرف سے انہیں دنیا کی حکومت ملے گی.جب انہیں عزت ملے گی ،رتبہ ملے گا، مال ملے گا تو وہ سُست نہیں ہو جائیں گے بلکہ اپنے فرائض کو پوری خوش اسلوبی سے ادا کریں گے اور وہ ہر وقت ایسے رہیں گے جیسے دیکھ رہے ہیں کہ کیا نقص واقعہ ہونے والا ہے اور وہ اس کو کس طرح دور کر سکتے ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدہ کے مطابق مسلمانوں کو مال دیا، دولت دی، عزت دی، رُتبہ دیا مگر وہ اسلام سے غافل نہیں ہو گئے.حضرت عبدالرحمٰن بن عوفؓ کے متعلق آتا ہے کہ جب وہ فوت ہوئے تو کئی کروڑ روپیہ کی جائداد اُن کے ترکہ میں تقسیم ہوئی(الطبقات الکبریٰ ذکر وصیۃ عبدالرحمٰن بن عوف و ترکتہ).اُن کی سالانہ آمد بھی لاکھوں دینار تھی مگر باوجود اس کے وہ رات اور دن اشاعتِ اسلام میں مشغول رہے اور مال و دولت کی فراوانی نے اُن کے اندر کسل یا غفلت پیدا نہیں کی.یہی حال حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ کا تھا وہ ساری دنیا کے بادشاہ ہو گئے مگر سُست اور غافل نہیں ہوئے بلکہ اپنے فرائض منصبی کو پوری تندہی سے ادا کرتے رہے حضرت عمررضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ حضرت عثمانؓ بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں مَیں ایک دفعہ باہر قبہ میں بیٹھا ہوا تھا اور اتنی شدید گرمی پڑ رہی تھی کہ دروازہ کھولنے کی بھی ہمت نہیں پڑتی تھی کہ اتنے میں میرے غلام نے مجھے کہا دیکھئے اس شدید دھوپ میں باہر ایک شخص پھر رہا ہے.میں نے پردہ ہٹا کر دیکھا تو مجھے ایک شخص نظر آیا جس کا منہ شدّتِ گرمی کی وجہ سے جُھلسا ہوا تھا.میں نے اُس سے کہا کہ کوئی مسافر ہو گا مگر تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ وہ شخص میرے قبّہ کے قریب پہنچا اور میں نے دیکھا کہ وہ حضرت عمرؓ ہیں.اُن کو دیکھتے ہی میںگھبرا کر باہر نکل آیا اور میں نے کہا اس گرمی میں آپ کہاں؟ حضرت عمرؓ فرمانے لگے بیت المال کا ایک اُونٹ گم ہو گیا تھا جس کی تلاش میں مَیں باہر پھر رہا ہوں(اسد الغابۃ زیر عنوان عمر بن عبد الخطاب).تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عَلَى الْاَرَآىِٕكِ يَنْظُرُوْنَ وہ ہوں گے تختوں پر مگر ہر وقت نگرانی اُن کا کام ہو گا.دنیا کی نعمتیں اور دنیا کے آرام اُن کو سست نہیں بنائیں گے وُہ اُن ارائک کے اندر سو نہ رہے ہوں گے بلکہ بیدار و ہوشیار ہوں گے.لوگوں کے حقوق کی دیکھ بھال کریں گے اور اپنے فرائض منصبی کو پوری خوش اسلوبی سے ادا کرتے چلے جائیں گے.
Page 465
تَعْرِفُ فِيْ وُجُوْهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيْمِۚ۰۰۲۵ تُو (اگر اُنہیں دیکھے تو) اُن کے چہروں میں نعمت کی شادابی محسوس کرے گا.حَلّ لُغَات.نَضْرَۃٌ.نَضْرَۃٌکے معنے ہوتے ہیں (۱)نعمت (۲)عیش (۳)غنٰی (۴)وَقِیْلَ الْحُسْنُ وَالرَّوْنَقُ وَاللُّطْفُ.یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نَضْرَۃٌ کے معنے حُسن، رونق اور لطف کے ہوتے ہیں (اقرب) اسی طرح جو ادیب ہیں انہوں نے تَعْرِفُ فِیْ وُجُوْھِھِمْ نَضْرَۃَ النَّعِیْمِ کے معنے کئے ہیں بَرِیْقُہٗ وَنَدَاہُ یعنی اس کی چمک اور اس کی تراوت (اقرب) پس تَعْرِفُ فِیْ وُجُوْھِھِمْ نَضْرَۃَ النَّعِیْمِ کے یہ معنےہوئے کہ تُو پہچانے گا اُن کے مُونہوں سے خدا تعالیٰ کی نعمت کی تازگی یا نعمت کا غناء.یا نعمت کا حُسن یا نعمت کی رونق یا نعمت کا لُطف.تفسیر.تَعْرِفُ فِيْ وُجُوْهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيْمِکے تین معنے اس آیت کے ایک معنے تو یہ ہیں کہ نعمتِ الٰہی اُن کے دلوں پر اس طرح نازل ہو گی کہ چہرہ سے خوشی پُھوٹ پُھوٹ پڑے گی.تَعْرِفُ فِیْ وُجُوْھِھِمْ سے پتہ لگتا ہے کہ یہ نعمت اُن کے دل پر نازل ہو گی اور اس طرح نازل ہو گی کہ اُن کے چہروں سے ظاہر ہو جائے گی اور وہ اُسے چھپا نہیں سکیں گے دنیا میں دو قسم کی باتیں ہوتی ہیں ایک وہ جنہیں چھپایا جا سکتا ہے اور ایک وہ جنہیں انسان چھپا نہیں سکتا بلکہ خود بخود ظاہر ہو جاتی ہیں.صحابہؓ کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نَضْرَۃَ النَّعِیْمِ اُن کے چہروں سے پُھوٹ پُھوٹ پڑے گی اور وہ خدا تعالیٰ کی اس نعمت کو لوگوں سے چھپا نہیں سکیں گے.فیج اعوج کے زمانہ میں مسلمانوں میں بعض ایسے ایسے صوفیاء گزرے ہیں جو دس دس بار ہ بارہ سال تک لوگوں سے خدمت لینے کے بعد اُنہیں دین کی کوئی ایک بات یا معرفت کا کوئی ایک نکتہ بتایا کرتے تھے اس کے مقابلہ میں صحابہؓ کی جو حالت تھی اُس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں اگر تلوار میری گردن پر رکھ دی جائے اور کوئی دشمن مجھے قتل کرنے لگے اور اُس وقت مجھے یاد آ جائے کہ رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات مجھے ایسی بھی یاد ہے جو ابھی تک میںنے بیان نہیں کی تو میں اُس کے تلوار چلانے سے پہلے پہلے اس بات کو بیان کر دُوں گا(صحیح بخاری کتاب العلم باب العلم قبل القول والعمل).تو ان کو یہ شوق تھا کہ خدا تعالیٰ کی باتوں کو دنیا میں زیادہ پھیلائیں.لیکن اور لوگوں کی یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں اگر ہم نے لوگوں کو اپنا علم بتا دیا تو پھر ہمارا علم ختم ہو جائے گا اور وہ بھی ہمارے برابر ہو جائیں گے.میں نے جب جلسہ سالانہ پر ذکر الٰہی کے متعلق تقریر کی تو ایک غیر احمدی صوفی جو باہر سے آئے ہوئے تھے
Page 466
اور میری اُس تقریر میں شامل تھے انہوں نے مجھے ایک رقعہ لکھا جس کا مضمون قریباً یہ تھا کہ آپ کیاغضب کر رہے ہیں کہ وہ نکتے جو صوفیاء دس دس بارہ بارہ سال تک لوگوں سے خدمت لینے کے بعد بتایا کرتے تھے اس طرح پے در پے بیان کرتے چلے جاتے ہیں.تو لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے علم کو چھپاتے ہیں لیکن ہمیں اس بات کی پروا بھی نہیں ہوتی کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہر وقت نئی سے نئی باتیں سکھاتا رہتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ علوم کا چھپانا ایسا ہی ہے جیسے صاف پانی کو گدلہ کر دیا جائے اور خدا تعالیٰ کا حکم بھی یہی ہے کہ اَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ (الضحٰی:۱۲) خدا تعالیٰ کی نعمتوں کو دنیا میں زیادہ سے زیادہ پھیلائو.پس فرمایا وہ خدا تعالیٰ کی نعمتوں کو چھپائیں گے نہیں بلکہ یوں معلوم ہو گا کہ وہ اُن کے چہروں سے پُھوٹ پُھوٹ کر ظاہر ہو رہی ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ کوئی شخص ملے تو اس کے سامنے ان نعمتوں کو رکھ دیں.دوسرےؔ معنے اس کے یہ ہیں کہ چونکہ اس آیت سے پہلے مادی ترقیات کا ذکر تھا اس لئے فرمایا کہ جب ان لوگوں کو مادی ترقیات ملیں گی تو اُن کا حال دوسرے لوگوں سے مختلف ہو گا.بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو نعماء ظاہری تو ملتی ہیں مگر ان کا دل اندر سے جل رہا ہوتا ہے.مثلًا کسی کو حکومت تو مل جاتی ہے مگر ا س کے خاندان میں ایسا تفرقہ اور فساد ہوتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے اس حکو مت نے میری زندگی کو وبال جان بنا دیا ہے یا امراء اور وزراء میں ایسی ایسی ریشہ دوانیاں ہوتی ہیں کہ حکومت ملنے کے باوجود انہیں دل کا اطمینان حاصل نہیں ہوتا.باورچی کھانا لاتا ہے تو وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں باورچی نے کھانے میں زہر نہ ملا دیا ہو.طبیب آتا ہے تو وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں یہ دوا میں زہر ملا کر مُجھے ہلا ک نہ کر دے.وزیر ملنے آتا ہے تو وہ ڈرتے ہیں کہ یہ کہیں مار نہ ڈالے.اِسی وجہ سے بادشاہوں کی طرف سے عجیب عجیب قسم کی حفاظتیں اور نگرانیاں کی جاتی ہیں.مگر فرماتا ہے ہم مومنوں کو وہ نعمتیں دیں گے جو نہ صرف اُن کے ظاہر پر ہو گی بلکہ اُن کے دل پر نازل ہوں گی اور اس وجہ سے یہ نہیں ہو گا کہ انہیں مادی کامیابی تو حاصل ہو جائے مگر ان کے دل خوش نہ ہوں بلکہ جہاں انہیں مادی ترقیات کے سامان ہماری طرف سے ملیں گے وہاں اُن کے دل بھی خوش ہوں گے اور مادی ترقی قلبی خوشی کے ساتھ ملی ہوئی ہو گی.کسبی اور نسبی غناء میں فرق تیسرےؔ معنے اس آیت کے یہ ہیں کہ ان کو غناء نعیم ملے گا یعنی حقیقی نعمت سے جو غناء پیدا ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے انسان غرباء پر رحم کرتا ہے وہ اُن کو حاصل ہو گا.دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اخلاق کسبی طور پر اچھے ہوتے ہیں اور بعض اخلاق نسلی طور پر اچھے ہوتے ہیں.مثلًا کسبی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ کسب والا اپنے مال کی اچھی طرح حفاظت کرتا ہے لیکن نسب والا اپنے مال کی اُس طرح حفاظت نہیں کرتا.چنانچہ کسبی طور
Page 467
پر مالدار ہو جانے والے کا نوکر اگر کچھ نقصان کر بیٹھے تو وہ اس سے بڑی سختی کا معاملہ کرتا ہے لیکن نسبی طور پر جن کے اندر غناء پایا جاتا ہے وُہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام عفو اور چشم پوشی کرنا ہے.نَضْرَۃٌ کے ایک معنے چونکہ غناء کے بھی ہیں اس لئے اس آیت کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ باوجود اس کے کہ اونٹ چراتے چراتے صحابہؓ کو حکومت کے تخت پر بٹھا دیا جائے گا وہ ویسے ہی وسیع الحوصلہ اور ویسے ہی بااخلاق ہوں گے جیسے نسلًا بعد نسلٍ وہ حکومت کرتے چلے آئے ہوں گویا وہ اخلاق جو کسب کے نتیجہ میں پیدا ہوتے ہیں وہ بھی ان کو حاصل ہوں گے اور جو نسلی طور پر حاصل ہوتے ہیں وہ بھی اُن میں اُسی دن پیدا ہو جائیں گے جس دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اُنہیں حکومت کے تخت پر بٹھا یا جائے گا.چنانچہ صحابہؓ کو دیکھ لو کوئی کمینگی ان کے فعل میں نظر نہیں آتی حالانکہ نَو دولتوں میں کچھ نہ کچھ وہ بات ضرور ہوتی ہے جسے انگریزی میں فاپشنیس FOPPISHNESS کہتے ہیں یعنی اُن کی طرف سے ایک قسم کا اظہار اس بات کا ہوتا ہے کہ ہم دولت مند ہیں اور اس طرح لوگوں کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ وہ ہیں جنہیں نئی نئی دولت ملی ہے مگر فرماتا ہے تم ان صحابہ کے چہروں کو دیکھو گے تو تمہیں ان پر غناء دولت نظر آئے گا تم ان کو دیکھ کر یہ خیال بھی نہیں کر سکو گے کہ انہیں نئی نئی دولت ملی ہے بلکہ یوں سمجھو گے کہ یہ نسلًا بعد نسلٍ اسی طرح حکمران چلے آئے ہیں.کمینگی اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر چڑنا اور اپنی دولت مندی کا اظہار کرنا اُن کے اندر نظر نہیں آئے گا.حضرت خلیفہ اوّل رضی اللہ عنہ ایک شخص کے متعلق جو بعد میں عیسائی ہو گیا سُنایا کرتے تھے کہ اُسے اپنے باپ دادا سے ورثہ میں کچھ جائداد ملی جو اُس نے تباہ و برباد کر دی اور وہ کنگال ہو گیا مگر اس حالت میں بھی اس کی عادت یہ تھی کہ جب وہ لاہور اسٹیشن پر اُترتا تو قُلی کوبلا کر اپنا رُومال اُسے پکڑا دیتا اور کہتا کہ میرے پیچھے پیچھے چلے آئو.آپ فرماتے کہ میں نے اُس سے پوچھا کہ تم یہ کیا کرتے ہو کہ تمہارے پاس سامان تو کوئی ہوتا نہیں اور تم صرف رومال جیب سے نکال کر قلی کو پکڑا دیتے ہو اور کہتے ہو کہ وہ اسے ہاتھ میں لٹکائے ہوئے تمہارے پیچھے پیچھے چلا آئے.اس پر وہ کہنے لگا اس کے بغیر شان نہیں ہوتی.تو یکدم انسان کو دولت مل جائے تو اُس کے اخلاق بگڑ جاتے ہیں مگر فرمایا یہ شتربان اونٹوں کو چراتے چراتے حکومت کے تخت پر جا بیٹھیں گے مگر نَو دولتوں والی کمینگی ان کے اخلاق میں نہیں پائی جائے گی بلکہ غناء نعیم اُن کے چہروں سے ظاہر ہوگا چنانچہ صحابہؓ جہاں بیٹھتے اس امر کا صاف صاف اقرار کرتے کہ ہم غریب ہوتے تھے، بھوکے رہتے تھے، کھانے اور پہننے کو کچھ نہیں ملتا تھا مگر محمد رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی برکت سے خدا نے ہمیں یہ نعمتیں عطا فرما دیں.ایران کے بادشاہ نے ایک دفعہ اُن سے کہہ دیا کہ تم ذلیل لوگ گوہ کھانے والے میرے
Page 468
ملک پر حملہ کرنے کے لئے آئے ہو تمہاری حیثیت ہی کیا ہے کہ تم ایسا کر سکو.کوئی دوسرا ہوتا تو وہ لڑ پڑتا کہ میری ہتک کی گئی ہے مگر صحابہؓ نے کہا آپ نے جو کچھ کہا بالکل درست ہے ہماری یہی حالت ہوا کرتی تھی مگر محمد رسول اللہ صلے اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کے آنے کے بعد ہماری یہ حالت نہیں رہی.اب ہم میں تغیّر پیدا ہو چکا ہے(تاریخ طبری زیر عنوان ثم دخلت سنۃ اربعۃ عشر ذکر ابتداء امر القادسیۃ).غرض غنائِ نعمت اُن کا جزو بن گئی تھی یہ نہیں تھا کہ وہ اپنی گزشتہ حالت کو چھپاتے ہوں اور سمجھتے ہوں کہ اگر لوگوں کو ہماری پہلی حالت کا پتہ لگ گیا تو ہماری ہتک ہو گی.وہ اس میں کوئی ہتک نہیں سمجھتے تھے بلکہ اس حالت سے دوسری حالت کو پانے میں خدا تعالیٰ کا ایک نشان دیکھتے تھے اس لئے اُس کے اظہار میں مزہ حاصل کرتے تھے.پس تَعْرِفُ فِیْ وُجُوْھِھِمْ نَضْرَۃَ النَّعِیْمِ کے ایک معنے یہ بھی ہیں کہ تو غناء نعمت اُن کے چہروں پر دیکھے گا نَو دولتوں والی حالت اُن میں نہیں دیکھے گا.يُسْقَوْنَ مِنْ رَّحِيْقٍ مَّخْتُوْمٍۙ۰۰۲۶ اُنہیں خالص سر بمہر شراب پلائی جائے گی.حَلّ لُغَات.رَحِیْق رَحِیْق خالص چیز کو کہتے ہیں.ا سی طرح رَحِیْق کے ایک معنے شراب کے ہیں.اور رَحِیْق ایک قسم کی خوشبو کوبھی کہتے ہیں.(تاج العروس) مَخْتُوْم:مَخْتُوْم خَتَمَ سے نکلا ہے اور خَتَمَ یَخْتُمُ خَتْمًا وَخِتَامًا کے معنے ہوتے ہیں طَبَعَہٗ وَ وَضَعَ عَلَیْہِ الْخَاتَمَ.اور عَلٰی کے ساتھ بھی یہ متعدی آتا ہے چنانچہ کہتے ہیں خَتَمَ الْکِتَابَ وَعَلَی الْکِتَابِ یعنی اُس نے کسی چیز پر مُہر لگائی.خَتَمَ الشَّیْئَ خَتْـمًا کے معنے ہوتے ہیں بَلَغَ اٰخِرَہٗ کسی چیز کو ختم کر دیا اور اُس کے آخر تک پہنچ گیا.خَتَمَ الْکِتٰبَ کے معنے ہوتے ہیں قَرَأَہُ کُلَّہٗ وَاَتَمَّہٗ.اُس نے تمام کتاب پڑھ لی اور اُسے تکمیل تک پہنچا دیا.خَتَمَ الصَّکَّ وَغَیْرَہٗ کے معنے ہوتے ہیں وَضَعَ عَلَیْہِ نَقْشَ خَاتِمِہٖ حَتّٰی لَا یَجْرِیْ عَلَیْہِ التَّزْوِیْرُ اُس نے چک یا ویسی ہی کسی چیز پر اپنی انگوٹھی سے مُہر لگا دی تاکہ کسی قسم کی دھوکا بازی نہ ہو.خَتَمَ الْعَمَلَ کے معنے ہوتے ہیں فَرَغَ مِنْہُ اس سے فارغ ہو گیا.اور خَتَمَ الْاِنَائَ کے معنے ہوتے ہیں سَدَّہٗ بِالطِیْنِ وَنَحْوَہٗ اس کا مٹی وغیرہ سے منہ بند کر دینا.وَفِیْ الْقُرْاٰنِ یُسْقَوْنَ مِنْ رَّحِیْقٍ مَّخْتُوْمٍ خِتَامُہٗ مِسْکٌا ور قرآن میں جو آتا ہے کہ یُسْقَوْنَ مِنْ رَّحِیْقٍ مَّخْتُوْمٍ.اُس کے بھی یہی معنے ہیں کہ وہ شراب سربمہر ہو گی.جیسے انگریزی دوائیوں کی جو شیشیاں آتی ہیں
Page 469
اُن کے مونہوں پر لاکھ لگا کر اوپر کارخانہ کی مہر لگی ہوئی ہوتی ہے اسی طرح وہ رحیقِ مختوم ہو گی یعنی اُس کا منہ بند ہو گا اور اُس پر مہر لگی ہوئی ہو گی.خَتَمَ الزَّرْعَ وَخَتَمَ عَلَیْہِ کے معنے ہوتے ہیں سَقَاہُ اَوَّلَ سَقْیَۃٍ.اس کو پہلی دفعہ پانی پلایا اور خَتَمَ اللّٰہُ لَہُ الْخَیْرَ کے معنے ہوتے ہیں اَتَمَّہٗ.اللہ تعالیٰ نے اُس پر خیر کا اتمام کر دیا.اور خَتَمَ عَلَی قَلْبِہٖ کے معنے ہوتے ہیں جَعَلَہٗ لَا یَفْھَمَ شَیْئًا وَ لَا یَخْرُجُ مِنْہُ شَیْءٌ.اُسے ایسا بنا دیا کہ نہ وہ کچھ سمجھتا ہے اور نہ اُس کے قلب میں سے کوئی چیز باہر آتی ہے یعنی نہ وہ خود سمجھتا ہے اور نہ دوسرے کو سمجھا سکتا ہے اور خَتَمَ اللّٰہُ لَہُ بِالْـخَیْرِ کے معنے ہوتے ہیں جَعَلَ لَہُ عَاقِبَۃً حَسَنَۃً.اس کا انجام اچھا کر دیا.اور کبھی خَتَمَ کی بجائے خَتَّمَ بھی بولتے ہیں جو مبالغہ کے لئے استعمال ہوتا ہے.(اقرب) تفسیر.يُسْقَوْنَ مِنْ رَّحِيْقٍ مَّخْتُوْمٍ کے یہ معنے ہیں کہ انہیں ایسی خالص شراب پلائی جائے گی جو مختوم ہو گی.مختوم کےایک معنے یہ ہیں کہ ایسی چیز جو ختم کر دی گئی ہو اور جس کے آخر تک انسان پہنچ جائے.پس رَحِیْقٍ مَّخْتُوْمٍ کے یہ معنے ہوئے کہ اُن کو ایسی لطیف اور اعلیٰ شراب ملے گی کہ جس کو ملے گی وُہ اُسے آخر تک ختم ہی کر جائے گا چھوڑے گا نہیں یعنی اپنے اپنے ظرف کے مطابق وہ ساری شراب پی جائے گا.ان معنوں سے ظاہر ہے کہ رحیقِ مختوم سے مراد عام شراب نہیں ہو سکتی.اسی طرح خِتَامُہٗ مِسْکٌا ور مِزَاجُہٗ مِنْ تَسْنِیْمٍ کے الفاظ کا آنا بتا رہا ہے کہ اس سے دنیوی شراب مراد نہیں ہے بہرحال یہ کوئی ایسی چیز ہے کہ یا تو اُسے اگلے جہان کی طرف منسوب کرنا پڑے گا اور یا اگر اس جہان کی طرف اُسے منسوب کیا جائے تو اس سے مراد کوئی ایسی چیز لینی پڑے گی جو ساری کی ساری پی جائے گی اور جس کا اپنے اپنے ظرف کے مطابق ایک قطرہ تک انسان باقی نہیں چھوڑے.رحیق سے مراد محبت الٰہی کی شراب میرے نزدیک یہاں رَحِیْق سے مراد محبتِ الٰہی کا نشہ ہے جو قرآن پیدا کرتا ہے.جس طرح شراب انسان کو مدہوش بنا دیتی ہے اسی طرح خدا تعالیٰ کا عشق انسان میں ایک قسم کی وارفتگی پیدا کر دیتا ہے اور اُسے ہر وقت اللہ تعالیٰ کے آستانہ پر جھکائے رکھتا ہے.شاعروں کو دیکھ لو وہ بھی اپنے معشوق کی آنکھ کو میخانہ کہتے ہیں.کیونکہ جس طرح شراب نشہ پیدا کرتی ہے اسی طرح محبوب کی آنکھ عاشق کو مدہوش بنا دیتی ہے.پس شعراء نے یہ محاورہ کثرت سے استعمال کر کے بتا دیا ہے کہ شراب سے مرادصرف مادی شراب نہیں ہوتی بلکہ محبت اور عشق کا نشہ بھی شراب کہلا سکتا ہے.غرض اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یُسْقَوْنَ مِنْ رَّحِیْقٍ مَّخْتُوْمٍ.انہیں شراب محبت پلائی جائے گی.اس سے مراد قرآن کریم کی تعلیم اور اس کے مضامین یا اُس کی روشنی میں محمد رسول اللہ
Page 470
صلے اللہ علیہ وسلم کے احکام ہیں کہ وہ اُن پر محبت کے نشہ میں مخمور ہو کر ایسا عمل کریں گے کہ اپنے عشق کو کمال تک پہنچا دیں گے.لفظ مختوم میں شراب کی خوبی کا اظہار مَخْتُوْمٌ کا لفظ ایک طرف شراب کی خوبی ظاہر کرتا ہے تو دوسری طرف پینے والوں کی خوبی کو بھی ظاہر کرتا ہے.اَور قوموں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعلیمیں تو دی گئیں مگر انہوں نے اُن پر اُدھورا عمل کیا.موسیٰ ؑ کو جو کچھ دیا گیا تھا اُس میں سے کچھ موسیٰ ؑکی قوم نے لیا اور کچھ نہ لیا.عیسٰیؑ کو جو کچھ دیا گیا تھا اُس میں سے بھی کچھ عیسٰیؑ کی قوم نے لیا اور کچھ نہ لیا.مگر محمد رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کی قوم وہ ہے کہ جب اُس نے خم کو منہ لگایا تو پھر اُس نے اُسے چھوڑا نہیں بلکہ وہ پیتی چلی گئی یہاں تک کہ اُسے ختم کر دیا یعنی اُس کی ایک ایک تعلیم کو اُس نے جامہ عمل پہنایا.اسی طرح مختومؔ کے لفظ سے قرآن کریم کی تعلیم کی خوبی بھی ظاہر ہے کیونکہ جس تعلیم کو چھوڑا نہ جائے اُس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ فطرتِ انسانی کے عین مطابق ہے.ایسی نہیں جو برداشت نہ ہو سکے.جس تعلیم کو انسان برداشت نہ کر سکتا ہو اُسے چھوڑ دیتا ہے مگر قرآن کریم کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ یَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّکْرِ (القمر :۱۸)ہم نے قرآن کو عمل کے لئے بالکل آسان کر دیا ہے اس کی کوئی تعلیم ایسی نہیں جس کا فطرت صحیحہ انکار کر سکتی ہو یا جس پر عمل کرنا اُس کے لئے دشوار ہو.پس اس ایک لفظ کے استعمال سے دونوں خوبیوں کی طرف اشارہ کر دیا.اِدھر قرآن کے متعلق بتا دیا کہ اس کی کوئی تعلیم ایسی نہیں جسے چھوڑا جا سکے انسان اس کی ایک ایک بات پر عمل کر سکتا ہے اور کسی کے متعلق یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس پر عمل کرنا میرے لئے مشکل ہے.دوسری طرف صحابہؓ کی تعریف کر دی کہ محمد رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کو وہ خادم اور ساتھی ملے تھے کہ جنہوں نے خُم سے مُنہ لگایا تو وہ خُم کا خُم ہی چڑھا گئے.خَتَمَ کے دوسرے معنے مہر کے ہوتے ہیں اور جس چیز پر مُہر لگی ہوئی ہو اُس میں کسی اور چیز کی آمیزش نہیں ہو سکتی.پس رَّحِیْقٍ مَّخْتُوْمٍ کے یہ معنے ہوئے کہ وہ پاک اور منزّہ ہو گی اور اُس میں کسی اور شئے کی آمیزش نہ ہو گی.یہ بھی قرآن کریم کی صفت ہے اور دشمن سے دشمن بھی سوائے شیعوں کے اقرار کرتا ہے کہ قرآن کریم ہر قسم کی آمیزش سے پاک ہے اور اس میں نہ کوئی چیز باہر سے داخل ہوئی ہے اور نہ اس کے اندر سے کوئی چیز باہرنکلی ہے.جس چیز پر مُہر لگی ہوئی ہو اُس میں یہی خصوصیت ہوتی ہے کہ نہ اُس کے اندر کی چیز باہر نکلتی ہے اور نہ باہر سے کوئی چیز اندر داخل ہوتی ہے اسی طرح قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو مختوم ہے.جب قرآن نازل ہوا تھا اس وقت رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم زندہ موجود تھے اور آپ کے ہوتے ہوئے کوئی شخص اس میں بگاڑ پیدا کرنے کی جرأت نہیں کر سکتا تھا.آپ
Page 471
کی وفات کے بعد خطرہ ہو سکتا تھا کہ اس میں کوئی بگاڑ پیدا نہ ہو جائے سو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بعد میں بھی یہ مختوم ہی رہے گا.یہاں چونکہ مسلمانوں کو بادشاہت عطا کئے جانے کا ذکر ہو رہا ہے اور بتایا گیا ہے کہ ایک زمانہ آئے گا جب مسلمان ارائک پر بیٹھیں گے اِس لئے اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جب مسلمان بادشاہ ہو جائیں گے.حکومت اُن کو حاصل ہو جائے گی.طاقت اُن کے پاس ہو گی اور وہ تمام قسم کے اختیارات اپنے ہاتھ میں رکھتے ہوں گے اُس زمانہ میں بھی قرآن بالکل محفوظ رہے گا اور کسی بادشاہ کو بھی یہ طاقت نہیں ہو گی کہ وہ اس میں تصرّف کر سکے.دنیا میں عام طور پر جب بادشاہت کا زمانہ آتا ہے تو لوگ چاہتے ہیں کہ اب ہم عیش کریں اور لُطف اُٹھائیں اور چونکہ مذہبی تعلیمیں اُن کے عیش میں حائل ہوتی ہیں اس لئے وہ اُن تعلیموں کو بدلنا شروع کر دیتے ہیں.مگر فرماتا ہے قرآن وہ ہے جو اسلامی ترقی کے زمانہ میں بھی بالکل خالص رہے گا نہ کوئی تعلیم اس میں سے خارج ہو سکے گی اور نہ کوئی نئی تعلیم اس میں داخل کی جا سکے گی.مسیحیوں میں اسی طرح خرابی پیدا ہوئی کہ جب روما کا بادشاہ عیسائیت میں داخل ہونے لگا تو اس نے کہا کہ مجھے عیسائیت قبول کرنے میں تو کوئی عذر نہیں مگر سبت کا دن جو ہفتہ کو منایا جاتا ہے وہ اتوار کے دن منا لیا جایا کرے کیونکہ ہماری قوم اتوار کا دن مناتی ہے ہفتہ کا دن نہیں مناتی.عیسائیوں نے سبت کا دن بدل کر اتوار کر دیا.پھر اُس نے کہا کہ ہماری قوم خالص توحید کا عقیدہ نہیں مان سکتی اس میں کچھ ایسے اشارے کنائے رکھ دیں جن کو دیکھ کر لوگوں کے لئے عیسائیت قبول کرنا آسان ہو جائے.انہوں نے یہ بات بھی مان لی اور کہا کہ ہم.باپ خدا بیٹا خدا اور روح القدس خدا کہنا شروع کر دیتے ہیں.چنانچہ وہ بادشاہ مع اپنی قوم کے عیسائیت میں شامل ہو گیا.عیسائیوں نے پہلے تو صرف لوگوں کو اپنے مذہب میں داخل کرنے کے لئے یہ تین نام رکھے تھے مگر آہستہ آہستہ یہ حقیقت میں تبدیل ہو گئے اور عیسائیوں نے ایک کی بجائے تین خدائوں کا عقیدہ اختیار کر لیا.تو جب بادشاہت آتی ہے.ترفّہ آتا ہے.طاقت حاصل ہوتی ہے تو مذہب میں کئی قسم کی تبدیلیاں شروع ہو جاتی ہیں.مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مسلمان جب آرائک پر بیٹھیں گے.جب تختِ حکومت ان کو نصیب ہو گا.جب طاقت اُن کو حاصل ہو گی.جب اقتدار اُن کو میسّر آئے گا تو اُس وقت بھی یہ کلام رحیقِ مختوم رہے گا اور بادشاہوں کو بھی یہ جرأت نہیں ہو گی کہ وہ اس میں اپنے مطلب کی کوئی چیز بڑھا دیں یا اس کی کسی تعلیم کو خارج کر دیں.گویا اسلام کی ترقی کے زمانہ میں بھی قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ کیا گیا ہے.اسی طرح اس میں شیعوں کا ردّ بھی ہو گیا جو خیال کرتے ہیں کہ قرآن کریم کا کچھ حصہ غائب ہے کیونکہ ختمؔ کے دونوں مفہوم ہوتے ہیں نہ اُس میں کوئی چیز پڑ سکتی ہے اور نہ اس میں سے کوئی چیز نکل سکتی ہے پس جو کتاب مختوم ہو اُس کے متعلق یہ کہنا کہ اُس کا ایک حصہ غائب ہو چکا ہے کسی طرح درست نہیں ہو سکتا.
Page 472
خِتٰمُهٗ مِسْكٌ١ؕ اُس کے آخر میں مُشک ہو گا.حَلّ لُغَات.خِتَام:خِتَام خَتَمَ کا مصدر ہے اور اس کے معنے ہیں اَلْفَصُّ مِنْ مَفَاصِلِ الْخَیْلِ.وَالْمَقْطَعُ وَالطِّیْنُ یُخْتَمُ بِہٖ عَلَی الشَّیْءِ.(اقرب) یعنی خِتَام گھوڑے کے جوڑ کو کہتے ہیں.اسی طرح خِتَام نظم کے آخری شعر کو بھی کہتے ہیں اور ختام اُس مٹی کوبھی کہتے ہیں جس کے ذریعہ کسی دوسری چیز پر مہر لگائی جائے.پس خِتَامُہُ مِسْکٌ کے یہ معنے ہوئے کہ (۱)وہ منہ بند کرنے والی چیز مشک کی ہو گی (۲)یا اُس کا آخری حصہ مشک ہو گا (۳)یا اس کے انتہاء تک مشک ہو گا.تفسیر.خِتٰمُهٗ مِسْكٌکے تین معنے اس آیت کے پہلے معنے یہ ہیں کہ اُس کی مُہر مُشک کی ہو گی یعنی جو اشیاء اُس کی حفاظت پر لگیں گی وہ بھی مُشک کی طرح ہو ں گی.یہ امر ظاہر ہے کہ قرآن کریم کی خدمت اور اُس کی حفاظتِ ظاہری کا کام حُفّاظ اور قراء کے سپرد ہے.وہ قرآن کریم کے خادم ہیں اور اس کی حفاظت کا کام سرانجام دے رہے ہیں.جس طرح مُہر کی یہ غرض ہوتی ہے کہ کوئی چیز باہر سے اندر داخل نہ ہواور کوئی چیز اندر سے باہر خارج نہ ہو اسی طرح اس آیت میں یہ بتایا گیا تھا کہ قرآن کریم کی خدمت پر ایسے انسان مقرر کئے جائیں گے جو مشک کی طرح خوشبودار ہوں گے یعنی وہ اعلیٰ درجہ کے نیک.اپنی ذمہ داری کو سمجھنے والے اور قرآن کریم کی حفاظت کا حق ادا کرنے والے ہوں گے.چنانچہ ہم دیکھتے ہیں چودہ سو سال گزر چکے ہیں مگر کوئی زمانہ ایسا نہیں ہوا جس میں حفّاظ کی ایک بڑی بھاری جماعت دنیا میں موجود نہ ہو اور وہ قرآن کریم کی خدمت نہ کر رہی ہو.پس خِتٰمُهٗ مِسْكٌ میں یہ پیشگوئی کی گئی تھی کہ اس کی حفاظت ظاہری کے لئے ہم ایسے لوگ کھڑے کر دیں گے جو نیکی اور تقویٰ میں اعلیٰ مقام رکھتے ہوں گے اور مشک کی طرح خوشبودار ہوں گے.دوسرےؔ معنے اس کے یہ ہیں کہ اُس کا آخر مشک کا ہو گا شراب کے نیچے ہمیشہ ایک چیز بیٹھ جاتی ہے جسے گارؔ کہتے ہیں.یورپ میں تو یہ قاعدہ ہے کہ وہ شراب کشید کرنے کے بعد اُسے سال سال دو دو سال تک پڑا رہنے دیتے ہیں اور اُس کے بعد اُسے شیشیوں میں بھرتے ہیں تاکہ جس قدر دُرد تہ نشین ہونی ہے وہ ہو جائے بلکہ بعض دفعہ تو دس دس پندرہ پندرہ سال تک شراب کو کشید کر کے رکھ دیتے ہیں.تاکہ انگور وغیرہ کے باریک ذرّے جو پانی میں ملے ہوئے ہوتے ہیں وہ آہستہ آہستہ تہ نشین ہو جائیں مگر پہلے زمانہ میں یہ رواج نہیں تھا اور شراب بنانے کے بعد جلد ہی
Page 473
بیچ دیتے تھے اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ شراب کی بوتل کے نیچے گار بیٹھ جاتی.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شراب کی دُرد تو گندی ہوتی ہے مگر قرآن وہ کتاب ہے جس کا دُرد بھی مشک کی طرح ہے.اب تم خود ہی سوچ لو کہ جس کا دُرد مشک کا ہو گا اس کا اصل کیسا ہو گا.دُرد کیا ہوتا ہے.دُرد ظاہری جسم کو کہتے ہیں مثلًا انگور یا کھجور وغیرہ سے شراب نکالی جائے تو انگور کے باریک باریک ذرّے یا کھجور وغیرہ کے ذرّات نیچے بیٹھ جاتے ہیں اور شراب اُن انگوروں یا کھجوروں کا سَت ہوتا ہے.پس چونکہ دُرد ظاہری جسم کو کہتے ہیں اور شراب ست ہوتا ہے اس لئے جب قرآن کے متعلق یہ کہا گیا کہ اس کی گار بھی مشک ہے تو اس گار سے مراد قرآن کریم کی ظاہری تعلیم ہو گی.پس آیت کا مطلب یہ ہے کہ قرآن وہ کتاب ہے کہ اس کی ظاہری تعلیم بھی اچھی ہے اور اس کی باطنی تعلیم بھی اچھی ہے.اس کی موٹی سے موٹی تعلیم جو کسی معاملہ کے متعلق ہو لے لو وہ مشک ہی مشک ہو گی اس سے تم قرآن کریم کی اعلیٰ درجہ کی روحانی تعلیمات کا اندازہ لگا سکتے ہو کہ وہ کیسی ہوں گی.تیسرےؔ معنے اس آیت کے یہ ہیں کہ جس طرح اس قرآن کی ابتداء اعلیٰ ہے اسی طرح اس کی انتہاء بھی اعلیٰ ہو گی.ابتداء میں محمد رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم جیسا عظیم الشان انسان اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام لے کر آیا اور آخری زمانہ میں مسیح موعودؑ اس کی اشاعت کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہو گا.گویا یہ وہ گلاس ہے جسے محمد رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے لوگ پینا شروع کریں گے اور پیتے چلے جائیں گے مگر آخر تک یہ مشک ہی مشک رہے گا یعنی ہمیشہ اللہ تعالیٰ ایسے آدمی مبعوث کرتا رہے گا جو قرآن کریم کی خدمت کریں گے اور اسلام کی اشاعت کا کام سرانجام دیں گے اور آخری زمانہ میں بھی ایسا آدمی پیدا ہو گا جو اس قرآن کی خوشبو کو ساری دنیا میں پھیلا دے گا.خِتٰمُهٗ مِسْكٌکا ظاہری الفاظ میں پورا ہونا یہاں ایک لطیفہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے اور وہ یہ کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کو مشک بڑا پسند تھا اور آپ ہمیشہ اُسے استعمال فرمایا کرتے تھے پس فرمایا اس کا ختام بھی مشک پر ہوگا یعنی ایسے انسان پر جو کثرت سے مشک استعمال کرنے والا ہو گا خدا تعالیٰ کی سُنت ہے کہ وہ بالعموم ایک ظاہری علامت شناخت کی بھی مقرر فرما دیتا ہے.جیسے ختم نبوت کے حقیقی معنوں کے ساتھ ایک نشان بھی رسول کریم صلے اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کی پشت مبارک پربنا ہوا تھا.
Page 474
وَ فِيْ ذٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُوْنَؕ۰۰۲۷ اور چاہیے کہ خواہش رکھنے والے (انسان) ایسی (ہی) چیز کی خواہش کریں.حَلّ لُغَات.تَنَافَسُوْا تَنَافَسُوْا فِیْ الشَّیْئِ کے معنے ہوتے ہیں نَافَسُوْاا ور نَافَسَ فِی الشَّیْئِ مُنَافَسَۃً وَنِفَاسًا کے معنے ہوتے ہیں رَغَبَ فِیْہِ عَلٰی وَجْہِ الْمُبَارَاۃِ فِی الْکَرَمِ.کہ مقابلہ کے جذبہ کے ساتھ نیک اور اچھے کاموں میں ایک دوسرے کے مقابل میں مشغول ہو گئے اور دوسرے معنے اس کے ہوتے ہیں بَالَغَ فِیْہِ وَغَالَ وَزَایَدَ.کسی کام کو حد سے زیادہ کرنا.اس میں غلُوّ سے کام لینا اور اس کام میں بڑھتے چلے جانا (اقرب) پس فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُوْنَ کے معنے یہ ہوئے کہ یہ وہ چیز ہے (یعنی رحیقِ مختوم کا ملنا) جس کے متعلق لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس کو لینے کے لئے ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کریں.تفسیر.اس بات کی دلیل کہ رحیق مختوم سے مراد کوئی مادی چیز نہیں اس آیت سے صاف پتہ لگتا ہے کہ رحیقِ مختوم کوئی مادی چیز نہیں بلکہ روحانی چیز ہے.کیونکہ اگر یہ مادی چیز ہوتی تو جو شخص ایک گلاس ہی پی سکتا ہے اُسے یہ کس طرح کہا جا سکتا تھا کہ وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے.تنافس وہاں ہی ہوتا ہے جہاں ایک شخص دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کر سکتا ہے.پس یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ روحانی چیز ہے جس میں دوسروں سے مقابلہ ہو سکتا تھا کوئی مادی چیز نہیں کہ جو محدود طور پر ہی استعمال کی جا سکتی ہے اور جس میں دوسرے سے مقابلہ کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا.چونکہ یہ روحانی نعمت تھی اور اس میں دوسروں سے مقابلہ کیا جا سکتا تھا اس لئے فرمایا کہ تم اگر اس معاملہ میں کسی دوسرے پر رشک کرو تو یہ بالکل جائز ہے.تم اگر کوشش کرتے ہو کہ دینی خدمات میں کوئی دوسرا تم سے بڑھ نہ سکے تو یہ نہ صرف جائز ہے بلکہ تمہارے لئے ضروری ہے کہ ایسا کرو.تَنَافُس کے معنے روز بروز بڑھتے چلے جانے کے ہیں.پس جہاں اس آیت کے یہ معنے ہیں کہ تم دوسروں کا مقابلہ کرو اور کوشش کرو کہ اپنے ساتھیوں سے بڑھ جائو وہاں اس کے ایک یہ معنے بھی ہیں کہ تم کوشش کرو کہ تمہارآج کا دن کل کے دن سے بڑھ جائے گویا مُبَارَاۃ کے تو یہ معنے ہیں کہ تم دوسروں کا مقابلہ کرو اور تزاید کے یہ معنے ہیں کہ تمہارا آج کا قدم تمہارے کل کے قدم سے آگے ہو یہ دو چیزیں اپنے سامنے رکھ لو پھر دیکھو کہ کس طرح تم جلد سے جلد ترقی حاصل کر لیتے ہو.
Page 475
وَ مِزَاجُهٗ مِنْ تَسْنِيْمٍۙ۰۰۲۸عَيْنًا يَّشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُوْنَ۠ؕ۰۰۲۹ اور اس میں تسنیم کی آمیزش ہو گی.(ہماری مراد اس) چشمہ (سے ہے) جس سے مقرب لوگ پئیں گے.حَلّ لُغَات.مِزَاجُہٗ.مِزَاجُہٗ مِنْ تَسْنِیْمٍ مَزَجَ الشَّیْءَ مَزْجًا وَمِزَاجًا کے معنے ہوتے ہیں خَلَطَہٗ بِہٖ.کسی چیز سے اُس کو ملا دیا.(اقرب) تَسْنِیْم سَنَّمَ الْکَلَأُ الْبَعِیْرَ کے معنے ہوتے ہیں عَظَّمَ سَنَامَہٗ.گھانس نے اونٹ کے کوہان کو بڑا کر دیا.سَنَّمَ فُلَانُ الْاِنَاء کے معنے ہوتے ہیں مَلَأَہٗ اُس نے اس کا برتن بھر دیا.سَنَّمَ الْمِکْیَالَ کے معنے ہوتے ہیں مَلَأَہٗ ثُمَّ عَمِلَ فَوْقَہٗ مِثْلَ السَّنَامِ مِنَ الطَّعَامِ.اُس نے برتن کو بھرا اور پھر بھر کر چوٹی دار بنا دیا.سَنَّمَ الشَّیْءَ کے معنے ہوتے ہیں عَلَاہُ اُس کو اونچا کیا اور سَنَّمَ الْقَبْرَ کے معنے ہوتے ہیں ضِدُّ سَطَّحَہٗ اُس نے قبر کو اونچا کیا (اقرب) پس تسنیم کے معنے ہوئے اونچا کرنا یا بھر دینا یاایسی چیز جو کہ اونچا کر دینے والی ہے یا بھر دینے والی ہے.تفسیر.تسنیم سے مراد الہام الٰہی اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شراب کے پیالوں کو الہامی پانی سے مدد دیتا رہے گا تاکہ ہر مزاج کا آدمی ہر زمانہ میں اس سے فائدہ اٹھاتا رہے.یعنی قرآن گو رحیق ہے مگر رحیق بھی اس پانی سے بنتی ہے جو اُس کے مناسب حال ہو.تھوڑے پانی کی ضرورت ہو تو اس میں تھوڑا پانی ملایا جاتا ہے.اور زیادہ پانی کی ضرورت ہو تو اُس میں زیادہ پانی ملایا جاتا ہے.گویا زمانہؔ اور ذوقؔ کے لحاظ سے اُس میں تبدیلی کی ضرورت ہوتی ہے اور گو چیز وہی رہے مگر اس کی شکل کو بدلنا ضروری ہوتا ہے تاکہ لوگ اس سے پوری طرح فائدہ اٹھاتے رہیں.پس مِزَاجُهٗ مِنْ تَسْنِيْمٍ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے اس طرف اشارہ فرما دیا کہ وہ ہر زمانہ کے لحاظ سے ایسے الہامات نازل کرتا رہے گا جو اس رحیق میں مناسب حال تمزیج کا باعث ہوں گے.پس تسنیمؔ سے مراد الہام کا پانی ہے جو قرآن میں ہر زمانہ میں ملایا جاتا رہا ہے اور بتایا گیا ہے کہ بغیر تازہ کلامِ الٰہی کے قرآن کریم اونچا نہیں ہوتا اُس کی عظمت اور اُس کی شان اور اُس کی فوقیت اس وقت صحیح طور پر ظاہر ہوتی ہے جب تسنیمؔ کا پانی اُس میں ملایا جائے.پس فرمایا قرآن بے شک رحِیْق مختوم ہے مگر ہر زمانہ میں ایسی ضرورتیں پیش آتی رہیں گی جن کے لئے تازہ کلامِ الٰہی کی ضرورت ہو گی.اس وقت ہم اپنا کلام نازل کریں گے جو قرآن کے لئے تسنیم کا موجب ہو گا.یعنی اُس کو اونچا کرنے اور اس کی شان اور عظمت کو ظاہر کرنے کا باعث ہو گا.آگے فرماتا ہے تمہیں کچھ پتہ ہے یہ تسنیم
Page 476
کیا چیز ہے؟ عَیْنًا یَّشْرَبُ بِھَا الْمُقَرَّبُوْنَ.یہ ایک چشمہ ہے جس سے مقرب لوگ پانی پیتے ہیں.یَشْرَبُ بِھَا کے متعلق بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس میں باء زائدہ ہے.بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہاں باء بمعنے مِنْ ہے اور بعض کہتے ہیں کہ یہاں بَاء حال کے لئے ہے یعنی عَیْنًا یَّشْرَبُ مَمْزُوْجًا بِھَا الْمُقَرَّبُوْنَ وہ ایک چشمہ ہے جس سے ملا کر رحیق پیتے ہیں.اور بعض نے کہا ہے کہ یہاں بَاء معنًا استعمال ہوئی ہے یعنے اصل میں یہ وہ جملے ہیں یَشْرَبُ وَیَلْتَذُّ بِھَا الْمُقَرَّبُوْنَ مقرب اس میں سے پیتے اور لذت حاصل کرتے ہیں.(تفسیر روح المعانی زیر آیت ھٰذا) یَشْرَبُ بِھَا الْمُقَرَّبُوْنَ نے صاف طور پر بتا دیا ہے کہ مِزَاجُہٗ مِنْ تَسْنِیْمٍ میں الہام الٰہی کا ہی ذکر کیا گیا تھا کیونکہ اس آیت میں یہ مضمون بیان کیا گیا ہے کہ قرآن کریم کی تعلیم کو تازہ الہام کی روشنی میں پیش کیا جاتا رہے گا.اور یہ الہام مقرب لوگوں پر نازل ہو گا یعنی امت محمدؐیّہ میں ہمیشہ ایسے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے جن کے دلوں میں تسنیم کا چشمہ پھوٹے گا اور وہ اس پانی کو پی کر قرآن کریم کی ایسی تشریحیں اور توضیحیں کریں گے جن سے ہر زمانہ کے لوگ فائدہ اُٹھا سکیں گے.اِنَّ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا كَانُوْا مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يَضْحَكُوْنَٞۖ۰۰۳۰ وہ (لوگ) جو مجرم ہوئے یقیناً مومنوں سے ہنسی (ٹھٹھا) کیا کرتے تھے.اور جب اُن کے پاس سے گزرتے تھے وَ اِذَا مَرُّوْا بِهِمْ يَتَغَامَزُوْنَٞۖ۰۰۳۱ تو ایک دوسرے کو آنکھ سے اشارے کیا کرتے تھے.حَلّ لُغَات.یَضْحَکُوْنَ:یَضْحَکُوْنَ ضَحِکَ سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے اور اَلضِّحْکُ (جو ضَحِکَ کا مصدر ہے) کے معنے ہیں اِنْبِسَاطُ الْوَجْہِ وَتَکَشُّرُ الْأَسْنَانِ مِنْ سُرُوْرِ النَّفْسِ یعنی ضَحک کے اصل معنی ہیں چہر ے پر کشادگی پیدا ہو جانا اور خوشی کے ساتھ دانت بجنے لگ جانا وَاسْتُعِیْرَ الضِّحْکُ لِلْسُخْرِیَّۃِ پھر استعارۃً اس کو تمسخر کے معنوں میں بھی استعمال کیا جانے لگا.چنانچہ کہتے ہیں ضَحِکْتُ مِنْہُ میں نے اس سے تمسخر کیا.وَرَجُلٌ ضُحَکَۃٌ یَضْحَکُ مِنَ النَّاسِ.وہ شخص جو لوگوں سے تمسخر کرے اُس کو ضُحَکَۃٌ کہتے ہیں.وَضُحْکَۃٌ لِمَنْ یُضْحَکُ مِنْہُ اور وہ شخص جس پر لوگ ہنسیں اس کو ضُحْکَۃٌ کہتے ہیں.ضحک سے مراد تعجب قرآن مجید میںآتا ہے وَکُنْتُمْ مِنْھُمْ تَضْحَکُوْنَ.اِذَاھُمْ مِنَّا یَضْحَکُوْنَ
Page 477
تَعْجَبُوْنَ وَتَضْحَکُوْنَ.اور معنے یہ ہیں کہ وہ تعجب کرتے ہیں.استعجاب کا اظہار کرتے ہیں.اور اس کے ساتھ ہی اُن کی حالت پر تعجب کر کے مذاق کرتے ہیں گویا ضحک کے معنے ایسی ہنسی کے ہیں جس کے ساتھ تعجب بھی شامل ہوتا ہے.وَیُسْتَعْمَلُ فِیْ السُّرُوْرِ الْمُجَرَّدِ.اور کبھی یہ لفظ خالی خوشی کے معنوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے خواہ ظاہری طور پر ہنسی آئی ہو یا نہ آئی ہو.وَاسْتُعْمِلَ لِلتَّعَجُّبِ الْمُجَرَّدِ تَارَۃً اور کبھی مجرّد تعجب کے لئے استعمال کیا جاتا ہے.یعنی خواہ صرف تعجب ہو.خوشی ہو یا نہ ہو.پھر مفردات کے مصنّف لکھتے ہیں وَمِنْ ھٰذَا الْمَعْنٰی قَصَدَ مَنْ قَالَ اَلضِّحْکُ یَخْتَصُّ بِالْاِنْسَانِ وَلَیْسَ یُوْجَدُ فِیْ غَیْرِہٖ مِنَ الْحَیَوَانِ انہی معنوں کی رُو سے بعض نے کہا ہے کہ ضحک انسان کے ساتھ مختص ہے کسی حیوان میں ضحک نہیں پایا جاتا (مفردات) تعجب ہے کہ مفردات والوں نے یہ کس طرح لکھ دیا حالانکہ تعجب جانوروں میں نمایاں طور پر پایا جاتا ہے چنانچہ جانور کے سامنے کوئی نئی چیز رکھ دی جائے تو وہ اُس کے پاس جاتا ہے اُسے تھوتھنی مارتا ہے.سونگھتا ہے اور جب دیکھتا ہے کہ وُہ چیز اُس کے کھانے کے قابل نہیں تو پیچھے ہٹ جاتا ہے.البتہ قہقہ مار کر ہنسنے والا کوئی جانور دکھائی نہیں دیتا.صرف ایک قلیل حد تک بندر میں ہنسی کا مادہ پایا جاتا ہے.پھر وہ کہتے ہیں وَلِھٰذَا الْمَعْنٰی قَالَ وَاِنَّہٗ ھُوَ اَضْحَکَ وَاَبْکٰی.قرآن کریم میں یہ جو آتا ہے کہ اِنَّہٗ ھُوَ اَضْحَکَ وَاَبْکٰی٭ اس کے معنے بھی تعجب کے ہی ہیں.اسی طرح مفردات والے قرآنی آیت اِمْرَاَتُهٗ قَآىِٕمَةٌ فَضَحِكَتْ میں ضَحِکَتْ کے معنے حَاضَتْ کرنے کے مخالف ہیں.وہ کہتے ہیں جس مفسّر نے یہ لکھا ہے اُس نے پہلے مفسّر کے معنے غلط سمجھے اس کی یہ مراد نہ تھی کہ ضَحِکَتْ کے معنے حَاضَتْ کے ہیں بلکہ اُس نے یہ لکھا تھا کہ اُس وقت جبکہ وہ ہنسیں اُن کو حیض آ گیا.مفردات والوں کے نزدیک اس آیت میں بھی ضَحِکَتْ کا لفظ تعجب کے معنوں میں استعمال ہوا ہے.چنانچہ وہ کہتے ہیں قرآن کریم کی دوسری آیتیں اِن معنوں کو ثابت کر دیتی ہیں.قرآن کریم میں آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو جب لڑکے کی خوشخبری ملی تو انہوں نے کہا ءَاَلِدُ وَ اَنَا عَجُوْزٌ وَّ هٰذَا بَعْلِيْ شَيْخًا١ؕ اِنَّ هٰذَا لَشَيْءٌ عَجِيْبٌ(ھود :۷۳) اسی طرح آتا ہے اَتَعْجَبِيْنَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ رَحْمَتُ اللّٰهِ وَ بَرَكٰتُهٗ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ١ؕ اِنَّهٗ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ (ھود: ۷۴) ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ ضَحِکَتْ کے معنے تعجب کے ہی ہیں کیونکہ ضَحِکَتْ کے لفظ کی اَتَعْجَبِیْنَ سے تشریح کی گئی ہے.مفردات کے مصنف یہ بات بھی کہتے ہیں کہ کوئی چیز اگر واضح ہو اور اس میں ٭ نوٹ: مفردات کے مصنف نے ھُوَ اَضْحَکُ وَ اَبْکٰی کی آیت ضَحِکَ سے مراد تعجب لیا ہے اور یہ معنے چسپاں ہوتے نظر نہیں آتے غالباً یہ آیت غلطی سے لکھی گئی ہے اصل آیت جس سے استنباط ہے وہ اس سے اگلی آیت ہے.
Page 478
میں چمک ہو تو وہ بھی استعارۃً ضاحک کہلاتی ہے.چنانچہ لکھا ہے سُمِّیَ الْبَرْقُ الْعَارِضُ ضَاحِکًا وَالْحَجَرَ یَبْرُقُ ضَاحِکًا وَسُمِّیَ الْبَلَحُ حِیْنَ یَتَفَتَّقُ ضَاحِکًا وَطَرِیْقٌ ضَحُوْکٌ وَاضِحٌ وَضَحِکَ الْغَدِیْرُ: تَلَأْ لَأَ مِنْ اِمْتِلَائِ ہٖ (مفردات) یعنی بجلی کو جب وہ بادلوں میں چمک رہی ہو ضاحکؔ کہتے ہیں.پتھّر جو چمک رہا ہو اُس کو بھی ضاحک کہتے ہیں.کھجور جب پختہ ہونے پر آئے اُسے بھی ضاحک کہتے ہیں.کھلے راستہ کو بھی طَرِیْقٌ ضَحُوْکٌ کہتے ہیں.اور وہ تالاب جو پانی سے خوب بھرا ہوا ہو اور اس کی کثرت کی وجہ سے چمک رہا ہو اس کے متعلق بھی کہتے ہیں کہ ضَحِکَ الْغَدِیْرُ.تالاب پانی کی کثرت سے چمک پڑا.یَتَغَامَزُوْنَ:یَتَغَامَزُوْنَ تَغَامَزَ سے مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے اور تَغَامَزَ الْقَوْمُ کے معنے ہوتے ہیں اَشَارَ بَعْضُھُمْ اِلٰی بَعْضٍ بِاَعْیُنِھِمْ.ایک دوسرے کی طرف آنکھوں سے اشارہ کیا.(اقرب) تفسیر.اسلام کی ترقی کی پیشگوئی پر کفار کا ہنسنا اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے.یقیناً وہ لوگ جنہوں نے جرم کیا اور جو خدا تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی وجہ سے کٹ چکے ہیں وہ اُن لوگوں سے جو کہ مومن ہیں تمسخر کرتے تھے.اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ضُعف اور اُن کی کمزوری کا ذکر کیا ہے اور بتایا ہے کہ اس زمانہ میں اُن کی حالت اس قدر کمزور ہو گی اور اُن کا دوبارہ ترقی اور عروج حاصل کرنا بظاہر اس قدر ناممکن ہو گا کہ کفّار اُن کو دیکھ دیکھ کر ہنسیں گے اور جب مسلمان اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین رکھتے ہوئے یہ کہیں گے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ پھر ترقی عطا کرنے والا ہے تو وہ کہیں گے یہ تو پاگل ہو گئے ہیں.ان کے دماغ سلامت نہیں رہے.کہ یہ خیال کرتے ہیں انہیں حکومت مل جائے گی.دنیا میں ایک بہت بڑی تبدیلی ان کے ذریعہ ہو گی اور نظامِ نَو کو یہ لوگ قائم کریں گے.وَاِذَا مَرُّوْابِھِمْ یَتَغَامَزُوْنَ.اَور جب وُہ ان کے پاس سے گزرتے ہیں تو وُہ اُن کو دیکھ کر آنکھیں مارتے ہیں.آنکھیں اُس وقت ماری جاتی ہیں جب انسان کسی دوسرے کے متعلق یہ یقین رکھتا ہو کہ وہ پاگل ہے اور وہ اپنے جنون کی حالت میں سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہو جائوں گا اور دنیا کا بادشاہ بن جائوں گا ایسی حالت میں لوگ اُس کو دیکھ دیکھ کر اپنے ساتھیوں کو توجہ دلانے کے لئے آنکھیں مارتے ہیں.اس خیال سے کہ اگر ہم نے منہ سے کوئی بات کی تو یہ پیچھے پڑ جائے گا.پس فرماتا ہے یہ لوگ بھی جب مومنوں کو دیکھیں گے اور اُن کی زبان سے یہ باتیں سُنیں گے کہ دنیا میں وہ ایک بہت بڑا تغیّر پیدا کرنے والے ہیں تو وہ آپس میں آنکھیں ماریں گے کہ یہ لوگ تو پاگل ہو گئے ہیں.یہ بالکل وہی نقشہ ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پر ہنسنے والوں کا تھا.جب حضرت نوح علیہ السلام
Page 479
اللہ تعالیٰ کے حکم کےماتحت کشتی تیار کررہے تھے تو کفار وہاں سے گزرتے اور اُن کو دیکھ دیکھ کر ہنستے تھے کہ یہ تو پاگل ہو گیا ہے.اسی طرح فرماتا ہے اُس زمانہ میں مومن بظاہر ایسے ہی بے کار کاموں میں مشغول نظر آئیں گے اور جب کفار اُن کو دیکھیں گے تو وہ ایک دوسرے کو آنکھیں ماریں گے کہ دیکھو جی یہ پاگل کیا کر رہے ہیں.اِس آیت سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ غالب قوم میں اُس وقت تسامح ہو گا اور اُن کے ظاہری اخلاق اور ہوں گے اور باطنی اَور.تغامزؔ انسان اُسی جگہ کرتا ہے جہاں وہ سمجھتا ہے کہ میرا کچھ کہنا اخلاق کے خلاف ہے اور یہ بات یوروپین قوموں میں نمایاں طور پر پائی جاتی ہے.اُن سے کوئی بات کرو وہ رسمی طور پر اُس وقت یہی کہیں گے کہ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیںمگر دل میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو پاگل ہیں.پس یَتَغَامَزُوْنَ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے یوروپین لوگوں کے اخلاق کا نقشہ کھینچ دیا ہے کہ وہ ظاہر کچھ کریں گے اَور اُن کے دل میں کچھ ہو گا.وَ اِذَا انْقَلَبُوْۤا اِلٰۤى اَهْلِهِمُ انْقَلَبُوْا فَكِهِيْنَٞۖ۰۰۳۲ اور جب گھر والوں کی طرف لوٹتے تھے تو (مسلمانوں کے خلاف) خوب باتیں بناتے ہوئے لوٹتے تھے.حَلّ لُغَات.فَکِھِیْنَ:فَکِھِیْنَ فَکِہٌ کی جمع ہے.کہتے ہیں فَکِہَ الرَّجُلُ فَکَھًا وَفَکَاھَۃً.کَانَ طَیِّبُ النَّفْسِ مَزَّاحًا ضَحُوْکًا.یعنی وہ بڑی اچھی طبیعت والا بامذاق اور ہنسنے والا ہےیا فَکِہَ الرَّجُلُ کے معنے ہوتے ہیں یُحَدِّثُ اَصْحَابَہٗ فَیُضْحِکُھُمْ.وہ اپنے ساتھیوں سے اس غرض کے لئے باتیں کرتا ہے تاکہ وہ ہنسیں.فَھُوَ فَاکِہٌ وَفَکِہٌ وَفَیْکَھَانُ.اسے فَاکِہٌ.فَکِہٌ اور فَیْکَھَانُ بھی کہتے ہیں اور فَکِہَ مِنْہُ کے معنے ہوتے ہیں تَعَجَّبَ.اُس نے تعجب کیا.(اقرب) تفسیر.فرماتا ہے ان لوگوں کی حالت یہ ہے کہ جب یہ اپنی قوم یا اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ کر جاتے ہیں تو خوب قہقے لگاتے اور مذاق کرتے جاتے ہیں کہ یہ کیسے بے وقوف لوگ ہیں.چونکہ فَکِہَ مِنْہُ کے معنے تعجب کرنے کے بھی ہیں اس لئے اس کے یہ معنے بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ تعجب کریں گے کہ یہ لوگ کیسے بے ہودہ خیالات میں پڑے ہوئے ہیں اور کیسی حماقت میں مبتلا ہیں کہ خیال کرتے ہیں اُن کی تعلیم اس ترقی اور تعلیم کے زمانہ میں پھیل جائے گی.
Page 480
وَ اِذَا رَاَوْهُمْ قَالُوْۤا اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ لَضَآلُّوْنَۙ۰۰۳۳ اور جب (بھی) انہیں دیکھتے تھے کہتے تھے کہ یہ لوگ تو (بالکل) گمراہ ہیں.تفسیر.رَاَوْھُمْمیں ھم کی ضمیر کا مرجع رَاَوْھُمْ کی ضمیر دونوں طرف جا سکتی ہے یعنی اَھْل کی طرف بھی اور مومنین کی طرف بھی.یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ اِذَا رَاَوْ اَھْلَھُمْ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اِذَا رَاَوْ الْمُؤْمِنِیْنَ یعنی بعض حالتوں میں تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ صرف تغامز کرتے ہیں.لیکن بعض حالتوں میں وہ مومنوں کو دیکھ کر رُک نہیں سکتے بلکہ ایک دُوسرے کو کہتے ہیں کہ یہ لوگ بڑے گمراہ اور بے وقوف ہیں اور چونکہ رَاَوْھُمْ کی ضمیر اَھْل کی طرف بھی جاتی ہے اس لئے اس کے یہ معنے بھی ہو سکتے ہیں کہ جب وہ اپنی قوم کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اِن لوگوں کو اچھی طرح دیکھ لیا ہے اِن سے ترقی کی امید کرنا بالکل غلط ہے.یہ لوگ آخر تباہ و برباد ہی ہوں گے.دنیا میں کوئی نیک تغیّر پیدا نہیں کر سکتے.اس صورت میں اُن کی یہ بات پہلی بات کی ضِد ہو گی.یعنی اُن کی حالت یہ ہے کہ وہ سامنے تو تغامز کرتے ہیں ایک پادری بھی آجائے تو وہ کہے گا کہ آپ لوگ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں لیکن جب اپنی قوم میں جاتے ہیں تو اسلام کے خلاف بڑی سخت کتابیں لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ لوگ تو بالکل گمراہ ہیں.وَ مَاۤ اُرْسِلُوْا عَلَيْهِمْ حٰفِظِيْنَؕ۰۰۳۴ حالانکہ وہ ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے.تفسیر.مَاۤ اُرْسِلُوْا عَلَيْهِمْ حٰفِظِيْنَمیں مغربی اقوام کے ایک خاصہ کی طرف اشارہ یہ بھی مغربی اقوام کی ایک خصوصیت ہے کہ وہ دوسرے ملکوں کی حفاظت کے بہانہ سے اُن پر قبضہ کرتے چلے جاتے ہیں.اور جب پوچھو کہ تم نےفلاں ملک پر کیوں قبضہ کیا؟ تو کہتے ہیں ہم نے تو اُس ملک کی حفاظت کے لئے یہ کام کیا ہے.انہوں نے اسی حفاظت کے بہانہ سے ہندوستانؔ لے لیا اور اسی حفاظت کے بہانہ سے افریقہ اور دوسرے ممالک پر قبضہ کر لیا.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ لوگ دوسروں کے محافظ بنا کر تو نہیں بھیجے گئے تھے پھر یہ کیوں ایسا کرتے ہیں کہ ہر ملک میں دخل دینا شروع کر دیتے ہیں اور اس کی حفاظت کا بہانہ بنا کر اس پر قبضہ کر لیتے ہیں.اس آیت
Page 481
میں درحقیقت سوال اور جواب دونوں آگئے ہیں مگر قرآن کریم کا یہ ایک نہایت ہی لطیف طریق ہے کہ وہ بعض دفعہ سوال چھوڑ دیتا ہے اور جواب دے دیتا ہے اور بعض دفعہ ایک حصہ بات کا بیان کر دیتا ہے اور دوسرا چھوڑ دیتا ہے کیونکہ وہ حصہ بیان کر دہ حصہ کی وجہ سے خودہی سمجھ میں آجاتا ہے.مَاۤ اُرْسِلُوْا عَلَيْهِمْ حٰفِظِيْنَمیں مضمون کا پہلا حصہ حذف ہے مَاۤ اُرْسِلُوْا عَلَيْهِمْ حٰفِظِيْنَکی آیت سارے مضمون کا ایک حصّہ ہے.بقیّہ حصہ محذوف ہے جو یہ ہے کہ یہ لوگ کیوں دوسروں کے ملکوں پر قبضہ کئے بیٹھے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اُن کے سپُرد یہ کام نہ کیا تھا کہ یہ دوسرے ملکوں میں گُھس کر اُن پر قبضہ کریں اور عذر یہ کریں کہ ہم تو اس کی حفاظت کے لئے آئے ہیں گویا یہ خدا تعالیٰ کے مقرّر کردہ داروغہ ہیں.فَالْيَوْمَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُوْنَۙ۰۰۳۵ پس جو ایمان لائے (وہ) اس (جزاء سزا کے) دن کفار پر ہنسیں گے.تفسیر.يَضْحَكُوْنَسے مرادہنسی کا بدلہ لینے کے فرماتا ہے اُس دن یا اگر فرض کیا جائے کہ وہ دن ذہن میں مستحضر کر کے بات کی جاتی ہے تو یُوں کہا جائے گا کہ آج کے دن مومن کفار سے اُن کی ہنسی کا بدلہ لیں گے.مومن کی یہ شان نہیں ہوتی کہ وہ ہنسی اُڑائے یا تمسخر اور استہزاء سے کام لے.قرآن کریم نے اس کو جہالت کا کام قرار دیا ہے.پس یہاںيَضْحَكُوْنَکے معنے ہنسی کرنے کے نہیں بلکہ ہنسی کا بدلہ لینے کے ہیں.عَلَى الْاَرَآىِٕكِ١ۙ يَنْظُرُوْنَؕ۰۰۳۶ چھپرکھٹوں پر بیٹھے ہوئے (ان کا سب حال) دیکھ رہے ہوں گے.تفسیر.یہاں پھر گزشتہ مضمون کو دُہرا دیا ہے کہ وہ تختوں پر بیٹھے ہوئے کس رنگ میں اُن سے بدلہ لیں گے.بُرے رنگ میں نہیں بلکہ اس اچھے رنگ میں کہ انہوں نے تو تختوں پر بیٹھ کر ظلم کئے تھے مگر وہ تختوں پر بیٹھ کر انصاف کریں گے.اور دیکھیں گے کہ کسی سے ناانصافی تو نہیں ہو رہی.یَنْظُرُوْنَسے مراد نگرانی کرنا یَنْظُرُوْنَ کے معنے اس جگہ نگرانی اور تعہد کے لئے جائیں گے کہ مومن اُس دن ہر معاملہ پر نظر رکھیں گے اور دیکھیں گے کہ کسی پر ظلم نہ ہو.
Page 482
هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَؒ۰۰۳۷ (اور آپس میں کہیں گےکہ) کیا کافروں کو جو کچھ وہ کیا کرتے تھے پورا بدلہ مل گیا (یا نہیں).تفسیر.ثُوِّبَ الْكُفَّارُ یا تو یَنْظُرُوْنَ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے کہ وہ دیکھیں گے کہ بدلہ کفار کو پورا پورا مل گیا ہے یا نہیں اور یا پھر اس کے یہ معنے ہیں کہ یُقَالُ لَھُمْ ھَلْ ثَوِّبَ.کفار سے کہا جائے گا کہ بتائو تمہارے اعمال کے نتائج نکل آئے ہیں یا نہیں تم سمجھتے تھے کہ اس تطفیف اور ظلم کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا اور تمہارا غلبہ قیامت تک چلتا چلا جائے گا اور عیسائی حکومتیں جو ظلم چاہیں گی لوگوں پر ڈھاتی رہیں گی.اب بتائو تمہیں اپنے مظالم کا بدلہ مل گیا ہےیا نہیں ملا؟
Page 483
سُوْرَۃُ الْاِنْشِقَاقِ مَکِّیَّۃٌ سورۃ الانشقاق.یہ سورۃ مکی ہے وَھِیَ خَمْسٌ وَّ عِشْرُوْنَ اٰیَۃًدُوْنَ الْبَسْمَلَۃِ اور اس کی بسم اللہ کے علاوہ پچیس آیتیں ہیں.بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۰۰۱ (میں) اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا (اور) بار بار رحم کرنے والا ہے (پڑھتا ہوں) سورۃ الانشقاق مکی ہے سورۃ الانشقاق مکی ہے.مضمون اور عبارت اور روایات سے ابتدائی زمانہ کی معلوم ہوتی ہے.اس کا مضمون سورۃ تکویر.انفطار.اور تطفیف کے ساتھ ملتا ہے.سورۃ انشقاق کا تعلق پہلی سورتوں سے اِ س سورۃ کا تعلق پہلی سورتوں سے ظاہر ہے اپنے ساتھ کی سورۃ سے اِس کا تعلق یہ ہے کہ اُس میں فرمایا تھا هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ.یعنی کفار جو سمجھتے تھے کہ ان کی بے اعتدالیوں کا بدلہ نہ ملے گا.جب ان کی شان وشوکت خاک میں مل جائے گی.اور مسلمان عروج حاصل کریں گے.تو ان کفار کو کہا جائے گا.لو! دیکھ لو اپنی تباہی.کیا تمہیں اپنی بے اعتدالیوں کا بدلہ ملا یا نہیں.اس وقت کفر کی طاقت ٹوٹ جائے گی.اور کفر کی تباہی کے ساتھ یہ لازمی ہوتا ہے.کہ ایمان کی ترقی ہو.کیونکہ روحانی اور جسمانی دنیا میں کبھی خلائے کامل نہیں ہوتا.جب بھی ایک چیز جاتی ہے.اس کی جگہ دوسری چیز لے لیتی ہے.اگر کفر جائے گا تو اس کی جگہ ایمان لے لے گا.اور اگر ایمان جائے گا تو اس کی جگہ کفر لے لے گا.چونکہ پچھلی سورۃ میںکفر کی تباہی کا ذکر تھا.اس لئے اس کے بعد آنے والی سورۃ میں ایمان کی ترقی کا ذکر فرمایا ہے.گویا اپنے ساتھ کی تین سورتوں سے جو اس کے ہم معنٰی اور ہم سلسلہ ہیں.اس کا یہ تعلق ہے کہ ان میں بنیادی مسئلہ کفر کی ترقی اور پھر اس کا انجام تھا اور اس میں بنیادی مسئلہ ایمان کے ظہور کا ہے.یوں ان پہلی تین سورتوں میں جس طرح آخری زمانہ کا ذکر ہے.اس سورۃ میں بھی آخری زمانہ کا ہی ذکر ہے.سورۃ انشقاق اور سورۃ انفطار کا باہمی جوڑ سورۃ تطفیف کے متعلق میں نے بتایا تھا کہ درحقیقت وہ سورۂ انفطار کے تسلسل میں ہے پس اصل مضمون جو اس سورۃ سے پہلے ہم سمجھیں گے.وہ سورۂ انفطار کا ہی ہو گا.
Page 484
سورۂ انفطار کو بھی آسمان کے لفظ سے شروع کیا گیا تھا.اور اس سورۃ کو بھی آسمان کے لفظ سے شروع کیا گیا ہے.اس جگہ آسمان کے ایسے پھٹنے کا ذکر کیا گیا تھا.جو خدا تعالیٰ کے غضب کو بھڑکاتا ہے اور اس سورۃ میں آسمان کے ایسے پھٹنے کا ذکر کیا گیا ہے.جو خدا تعالیٰ کی رحمت کو جذب کرتا ہے.پس یہ سورۃ اپنی پہلی تین سورتوں سے مل کر اسلام کے دوسرے غلبہ اور اس سے پہلے کی خرابیوں اور تلخیوں کے ذکر پر مشتمل ہے.اَور ہر سورۃ میں ایک نیا رنگ اختیار کیا گیا ہے.سورۂ انشقاق میں بھی آخری زمانہ کا ذکر ہے.مگر اس طرح کہ اس زمانہ میں خدا تعالیٰ آسمانی علوم کو ظاہر کرے گا اور زمین ان کو قبول کرے گی.گویا پہلی سورۃ میں آسمان پھٹنے سے مراد مسیحیت کے غلبہ کا ذکر تھا اور اِس سورۃ میں آسمان کے پھٹنے سے مراد علومِ آسمانیہ کا ظہور یا آسمانی بارش کا نزول ہے.اِسی وجہ سے اَذِنَتْ لِرَبِّهَا کے لفظ بعد میں رکھے گئے ہیں.جس میں بتایا ہے.کہ اس جگہ آسمان کا پھٹنا اللہ تعالیٰ کی مخالفت میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت میں ہے.اِذَا السَّمَآءُ انْشَقَّتْۙ۰۰۲ جب آسمان پھٹ جائے گا.حَلّ لُغَات.اِنْشَقَّتْ اِنْشَقَّتْ اِنْشَقَّ سے مؤنث کا صیغہ ہے.اور اِنْشَقَ شَقَّ سے باب انفعال ہے اور شَقَّ الشَّیْءَ شَقًّاکے معنے ہوتے ہیں.صَدَعَہٗ وَفَرَّقَہٗ اس کے اندر شگاف کر دیا.اور اس کو الگ الگ کر دیا.چنانچہ اسی سے یہ محاورہ ہے.کہ شَقَّ عَصَا الْمُسْلِمِیْنَ اَیْ فَرَّقَ جَمْعَھُمْ وَکَلِمَتَہُمْ اس نے مسلمانوں کے عصا کو پھاڑ دیا.یعنی ان کی جمعیت اور اتحاد کو پراگندہ کر دیا.اور شَقَّ نَابُ الْبَعِیْرِ اَوْ نَابُ الصَّبِیِّ وَشَقَّ الصُّبْحُ شُقُوْقًا کے معنی ہوتے ہیں طَلَعَ دانت نکل آئے یا صبح ظاہر ہوگئی اور شَقَّ النَّبْتُ شُقُوْقًا اس وقت کہتے ہیں جب پہلی روئیدگی زمین میں سے پھوٹتی ہے.(اقرب) اور جب صرف شَقَّ الْعَصَا کہیں تو اس کے معنے ہوتے ہیں فَارَقَ الْجَمَاعَۃَ وہ جماعت سے الگ ہو گیا.اور شَقَّقَ بھی انہی معنوں میں آتا ہے.کہتے ہیں شَقَّقَ الْحَطَبَ شَقَّہٗ اُس نے لکڑی چیری.اور اِنْشَقَّ الشَّیْءُ کے معنی ہوتے ہیں.اِنْفَتَحَ فِیْہِ فُرْجَۃٌ وَاِنْصَدَعَ کسی چیز میں شگاف ہو گیا.اور اِنْشَقَّ الْاَمْرُ کے معنی ہوتے ہیں.اِنْفَرَقَ وَتَبَدَّدَ اِخْتِلَافًا تفرقہ پیدا ہو گیا.اور افتراق کی وجہ سے اس میں پراگندگی پیدا ہو گئی.اور اِنْشَقَّ الْفَجْرُ کے معنی ہوتے ہیں طَلَعَ فجر ہو گئی.اور اِنْشَقَّ الْبَرْقُ کے
Page 485
معنی ہوتے ہیں اِنْعَقَّ بجلی بادلوں میں کوندتی ہوئی نکل گئی (اقرب) پس اِنْشَقَّتْ کے معنے ہوں گے کوئی چیز پھٹ گئی.اور اس کے پھٹنے سے دوسری چیز جو اس کے پیچھے تھی نظر آنے لگی.تفسیر.جیسا کہ حل لغات سے ظاہر ہے اِذَا السَّمَآءُ انْشَقَّتْ کے معنی یہ ہیں کہ آسمان پھٹ گیا.یا یہ کہ آسمان ظاہر ہو گیا.کیونکہ انشقاق کسی چیز کے باہر نکل آنے اور بجلی کے کوندنے اور فجر کے طلوع کرنے کو بھی کہتے ہیں.درحقیقت انشقاق کے اصل میں دو ہی نتیجے ہوتے ہیں.یا تو کوئی چیز پھٹ کر ناکارہ ہو جاتی ہے یا پیچھے جو چیز رُکی ہوئی ہو وُہ باہر آجاتی ہے.بعض دفعہ کسی چیز کے باہر نکلنے میں کوئی روک حائل ہوتی ہے.جب سوراخ ہو جائے.تو وہ چیز باہر آجاتی ہے.اِس لحاظ سے آسمان پھٹنے سے عذاب اور رحمت دونوں کا نزول مراد لیا جا سکتا ہے.کیونکہ خدا کے پاس عذاب بھی ہے اور اس کے پاس رحمت بھی ہے.اِذَا السَّمَآءُ انْشَقَّتْمیں آسمان کا پھٹنا بطور رحمت کے ہے اِذَا السَّمَآءُ انْفَطَرَتْ میں آسمان کا ایسا پھٹنا مراد تھا.جس کے پیچھے عذاب تھا.مگر اِس سورۃ میں ایسا پھٹنا مراد ہے جس کے پیچھے خدا تعالیٰ کا کلام یا الہام ہے یہ ایسی ہی بات ہے.جیسے قرآن کریم میں دوسری جگہ آتا ہے.اَوَ لَمْ يَرَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْۤا اَنَّ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَا(الانبیاء:۳۱) یعنی کفار اِس امر پر کیوں غور نہیں کرتے کہ آسمان اور زمین دونوں بالکل گیند سے بنے ہوئے تھے.پھر ہم نے آسمان کو بھی پھاڑ دیا.اور زمین کو بھی.یہاں آسمان پھٹنے سے نزولِ عذاب مراد نہیں.کیونکہ آگے فرماتا ہے.وَ جَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ١ؕ اَفَلَا يُؤْمِنُوْنَ اور ہم نے پانی سے ہر شے کو زندہ کیا ہے کیا وہ ایمان نہیں لاتے.پس یہاں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا ذکر فرما رہا ہے.کہ آسمان اور زمین دونوں بالکل بند تھے.اور اُن میں کوئی سوراخ نہ تھا.نہ زمین اپنی روئیدگی نکالتی تھی.نہ آسمان پانی برساتا تھا.پھر ہم نے دونوں کو پھاڑ دیا.جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آسمان سے پانی اترنا شروع ہو گیا.اور زمین میں سے روئیدگی نکلنی شروع ہو گئی.یہی مضمون یہاں دوسرے الفاظ میں ادا کیا گیا ہے فرماتا ہے اِذَا السَّمَآءُ انْشَقَّتْ عذابِ الٰہی کے نزول کی وجہ سے اور کفر ،شرک اور بدعت کے پھیلنے کی وجہ سے جن کا پہلی سورتوں میں ذکر کیا گیا ہے.آسمان نے اپنی برکتیں روک لی تھیں.اور وہ بالکل سمٹ گیا تھا.اس میں کوئی سوراخ نہ تھا.جس میں سے زمین والوں پر رحمتیں نازل ہوتیں صرف وہی سوراخ کھلا تھا جس میں سےغضب اور عذاب نازل ہوتے ہیں.پھر خدا نے اپنے بندوں پر رحم کیا.اور اسے اس طرح پھاڑا.کہ اس میں سے رحم نازل ہونا شروع ہو گیا.چنانچہ آگے اس کی دلیل دے دی کہ اَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَ حُقَّتْ یہ آسمان کا پھٹنا فرمانبرداری اور اطاعت کے لئے ہے جس طرح پہلا پھٹنا نافرمانی اور گناہ کی وجہ سے تھا یعنی اب وہ رحمت
Page 486
کے لئے اور کلامِ الٰہی کے نزول کے لئے پھٹا ہے.وَ اَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَ حُقَّتْۙ۰۰۳ اور اپنے رب (کی بات سننے) کے لئے کان دھرے گا اور یہی (اس پر) فرض ہے.حَلّ لُغَات.اَذِنَتْ اَذِنَتْ اَذِنَ سے مؤنث کا صیغہ ہے.اور اَذِنَ بِالشَّیْءِ اِذْنًا وَاَذَنًا وَاَذَانًا وَاَذَانَۃً کے معنی ہوتے ہیں عَلِمَ بِہٖ.یعنی اس کا علم حاصل کیا.اور اَذِنَ لَہٗ فِیْ الشَّیءِ اِذْنًا وَاَذِیْناً کے معنی ہوتے ہیں اَبَاحَہٗ لَہٗ اس کو اجازت دی.اور اَذِنَ اِلَیْہِ اَذَناً کے معنی ہوتے ہیں اِسْتَمَعَ اس کی بات کو سنا (اقرب) مفردات میں لکھا ہے.وَاَذِنَ اِسْتَمَعَ نَحْوَ قَوْلِہٖ وَاَذِنَتْ لِرَبِّھَا وَحُقَّتْ یعنی اَذِنَ کے معنی سننے کے بھی ہوتے ہیں.بخاری میں حدیث آتی ہے.کہ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ مَااَذِنَ اللّٰہُ لِشَیْءٍ مَا اَذِنَ لِنَبِیِّ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ اَنْ یَّتَغَنَّی بِالْقُرْاٰنِ (بخاری کتاب فضائل القرآن باب من لم یتغنّ بالقراٰن) یعنی اللہ تعالیٰ کسی بات کو اس طرح شوق سے نہیں سنتا جیسے اپنے نبی کی بات کو جب وہ قرآن پڑھ رہا ہو.حُقَّتْ حُقَّتْ حَقَّ سے ہے.اور حَقَّ عَلَیْکَ وَ یَحِقُّ عَلَیْکَ وَحُقَّ لَکَ اَنْ تَفْعَلَ کَذَا کے معنی ہوتے ہیں وَجَبَ عَلَیْکَ تجھ پر یہ بات واجب ہے (اقرب) پس اَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَ حُقَّتْ کے معنی یہ ہوئے کہ حُقَّ لَھَا اَنْ تَفْعَلَ کَذَا.یعنی وہ اپنے رب کی بات پر کان دھرے گا.اور وہ اسی لائق ہے کہ اپنے رب کی بات کو اچھی طرح سنے.اس پر غور کرے اور اس کے حکم کی اطاعت کرے.تفسیر.اِس آیت میں بتایا گیا ہے.کہ آخری زمانہ میں جہاں خدا تعالیٰ کے غضب نازل ہوں گے.اور اس کی طرف سے کئی قسم کی آفات اتریں گی.وہاں یہ بھی سامان کئے جائیں گے کہ آسمان سے کلامِ الٰہی نازل ہو.انشقاقِ آسمان درحقیقت بارش پر دلالت کرتا ہے.اور مطلب یہ ہے کہ ایک قوم کے لئے آسمان پھٹے گا.تاکہ اس پر غضب کا مینہ برسے اور ایک اور قوم پر بھی آسمان پھٹے گا.مگر اس لئے کہ اس پر رحمت کی بارش نازل ہو.اور اللہ تعالیٰ کے کلام اور آسمانی علوم کا ظہور ہو.گویا قرآن مردہ ہو چکا ہو گا.مگر اس زمانہ میں اللہ تعالیٰ پھر علومِ قرآنیہ کو آسمان سے نازل کرے گا.اور اپنے کلام اور الہام کی بارش برسائے گا.انشقاق سماء سے مراد پیدائش آدم اس آیت کے ایک اور معنی بھی ہو سکتے ہیں.اور وہ یہ کہ قرآن کریم
Page 487
میںدوسری جگہ آتا ہے.وَ انْشَقَّتِ السَّمَآءُ فَهِيَ يَوْمَىِٕذٍ وَّاھِیَۃٌ.وَّ الْمَلَكُ عَلٰۤى اَرْجَآىِٕهَا (الحاقۃ :۱۷.۱۸) یعنی آسمان پھٹے گا.اور فرشتے اطاعت اور فرمانبرداری کے لئے اس کے کناروں پر آ کر کھڑے ہو جائیں گے.اِ س آیت کو مدِّنظر رکھتے ہوئے زیر تفسیر آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ جس طرح آدمِ اوّل کی پیدائش پر فرشتوں سے کہا گیا تھا کہ اُسْجُدُوْا لِاٰدَمَ اِسی طرح آخری زمانہ میں آسمان پھٹے گا.اور فرشتے اطاعت کے لئے کھڑے ہو جائیں گے.یعنی ایک نیا روحانی آدم پیدا کیا جائے گا اَور فرشتے احکامِ الٰہی کی بجاآوری کے لئے کمربستہ و تیار ہو جائیں گے.پس اِذَا السَّمَآءُ انْشَقَّتْ.وَ اَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَ حُقَّتْ کا ایک مطلب یہ ہوا کہ ایک نیا آدم پیدا ہو گا ایک نئی رُوح دنیا میں آئے گی.آسمان کے دروازے کھول دئیے جائیں گے اور فرشتے بار بار آئیں گے تاکہ اس کی مدد اور نصرت کریں.اَذِنَتْ لِرَبِّهَا کےساتھ لفظ حُقَّتْ لانے کی وجہ اِس جگہ یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اَذِنَتْ لِرَبِّهَا کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حُقَّتْ بھی فرمایا ہے کہ آسمان اپنے رب کی بات پر کان دھر ے گا اور وُہ اِسی بات کا اہل تھا.یہ حُقَّتْ کا لفظ انقیاد کی شدّت بتانے کے لئے استعمال کیا گیا ہے.یوں خالی انقیاد کا اظہار بھی کافی تھا.مگر حقّت کے معنی یہ ہیں کہ وہ اسی لائق تھا اور اِسی غرض کے لئے اس کو بنایا گیا تھا اور جو چیز کسی خاص غرض کے لئے بنائی جاتی ہے اس کا فعل دوسروں سے زیادہ اعلیٰ ہوتا ہے.ایک کام چھری کا ہوتا ہے.ہمارے پاس چاقو ہو.تو وہ بھی چھری کا کام دے دے گا.مگر وہ کام ایسا ا چھا نہیں ہو گا جیسے چھری سے کام ہو سکتا تھا.یا ایک کام تلوار کا ہے.ہمارے پاس تلوار نہ ہو.تو گو چھری بھی کچھ کام دے جائے گی.مگر ایسا اچھا کام نہیں دے گی.جیسے تلوار دے سکتی تھی.تو جو چیز جس غرض کے لئے بنائی گئی ہو.اُس کا فعل دُوسری چیزوں سے زیادہ نمایاں ہوتا ہے.پس حُقَّتْ کے معنی یہ ہوئے کہ وہ اطاعت اور فرمانبرداری میں کمال دکھائیں گے.کیونکہ ان کو خدا نے پیدا ہی اِس لئے کیا ہے.اور ان کے اندر اس نے یہ قابلیت رکھی ہے.کہ وہ خدا تعالیٰ کے احکام کو پورا کریں.وَ اِذَا الْاَرْضُ مُدَّتْۙ۰۰۴ اور جب زمین پھیلا دی جائے گی.حَلّ لُغَات.مُدَّتْ مُدَّتْ مَدَّ سے ہے.اور مَدَّاللّٰہُ الْاَرْضَ کے معنی ہوتے ہیں بَسَطَھَا زمین کو خدا نے پھیلایا.مَدَّاللّٰہُ عُمُرَہٗ کے معنی ہوتے ہیں اَطَالَہٗ اللہ نے اس کی عمر کو لمبا کر دیا.اور مَدَّ الْمَدْیُوْنَ کے معنے
Page 488
ہوتے ہیں اَمْھَلَہٗ مقروض کو اس نے مہلت دے دی.اور مَدَّالْقَوْمُ کے معنی ہوتے ہیں صَارَلَھُمْ مَدَ دًا وَاَغَاثَھُمْ بِنَفْسِہٖ اس نے لوگوں کی مدد کی.اور ان کی فریاد کو سنا وَفِی الِّلسَانِ مَدَدْتَ الْاَرْضَ مَدًّا اِذَازِدْتَ فِیْھَا تُرَابًا اَوْسَمَادًا مِنْ غَیْرِھَا لِیَکُوْنَ اَعْمَرَلَھَا وَاَکْثَرَ رَیْعاً لِزَرْعِھَا.لسان میں لکھا ہے کہ مَدَدْتَ الْاَرْضَ اُس وقت کہتے ہیں جب زمین کے اندر اچھی مٹی جو تازہ ہو.یا مٹی میں ملی ہوئی کھاد ڈالی جائے.تاکہ کھیتی خوب ہو.اور مَدَّ السَّرَاجَ بِالسَّلِیْطِ کے معنی ہوتے ہیں صَبَّ فِیْہِ زَیْتاً اس نے دیئے میں تیل ڈالا (اقرب) پس مُدَّتْ کے معنے ہوں گے پھیلائی جائے گی.(۲)اس کی کمی پُوری کی جائے گی.اس کو مہلت دی جائے گی.(۳)اس کی فریاد سنی جائے گی.تفسیر.وَ اِذَا الْاَرْضُ مُدَّتْکے چار معنے اوپر بتایا جا چکا ہے کہ مَدَّ اللّٰہُ الْاَرْضَ کے معنی ہوتے ہیں بَسَطَھَا.زمین کو خدا نے پھیلا دیا.اِس لحاظ سے وَاِذَاالْاَرْضُ مُدَّتْ کے معنی ہوں گے جب زمین پھیلائی جائے گی.قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ایک دوسرے مقام پر فرماتا ہے.وَ الْاَرْضَ مَدَدْنٰهَا (الحجر:۲۰ )کہ زمین کو ہم نے پھیلا دیا ہے پس جبکہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی پھیلا رکھا ہے.تو اس کے بعد یہ فرمانا کہ وَاِذَا الْاَرْضُ مُدَّتْ پھر ایک زمانہ میں زمین پھیلائی جائے گی.اس کے سوائے اس کے اور کوئی معنی نہیں ہو سکتے.کہ پہلی زمین کفر اور گناہ کی وجہ سے تباہ ہو چکی ہو گی.تب اللہ تعالیٰ ایک نئی زمین لوگوں کے لئے پیدا فرمائے گا.پس وَاِذَا الْاَرْضُ مُدَّتْ کے الفاظ ایک نئی زمین کی پیدائش کے معنوں میں استعمال کئے گئے ہیں.اور بتایا گیا ہے کہ زمین اپنی پہلی قابلیتیں کفر اور گناہوںکی کثرت کی وجہ سے کھو چکی ہو گی.اس لئے آسمان کو پھاڑنے کے بعد خدا تعالیٰ زمین کو بھی اِس قابل بنائے گا.کہ اس کے انوار کو جذب کر سکے.مَدَّ کے دوسرے معنی اَطَالَ اللّٰہُ عُـمُرَہٗ کے ہوتے ہیں.کہ اللہ نے اس کی عمر کو لمبا کر دیا.اِسی طرح کہتے ہیں مَدَّ الْمَدْیُوْنَ: اَمْھَلَہٗ.اس نے اپنے مقروض کو مہلت دے دی اِ س لحاظ سے آیت کے یہ معنی ہوں گے کہ جب کفر اور شرک کی کثرت کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے گا.اس وقت زمین بھی اپنے گناہوں کی وجہ سے اس بات کی مستحق ہو گی کہ اسے تباہ کر دیا جائے.لیکن اس نئے آسمانی شگاف کی وجہ سے جس سے اللہ تعالیٰ کے انوار اوراس کی برکات نازل ہوں گی زمین اس بات کی مستحق ہو گی کہ اسے مہلت دی جائے.اور اُس کی عمر کو لمبا کر دیا جائے.اگر نبی کے آنے کے ساتھ ہی قیامت آجائے.تو اُس کی بعثت کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا.ضروری ہوتا ہے کہ زمین والوں کو مہلت دی جائے.اور انہیں موقعہ دیا جائے.کہ وہ خدا تعالیٰ کی باتوں پر غور کریں.پس وَاِذَا الْاَرْضُ مُدَّتْ کے یہ
Page 489
معنی ہیں.کہ زمین کی عمر لمبی کر دی جائے گی.اور اسے مہلت دی جائے گی.کہ وہ خدا تعالیٰ کی برکات سے فائدہ اٹھا سکے.اسی طرح مَدَّ الْقَوْمَ کے ایک معنی ہیں صَارَ لَھُمْ مَدَدًا وَاَغَاثُھُمْ بِنَفْسِہٖ ان معنوں کے لحاظ سے وَاِذَا الْاَرْضُ مُدَّتْ کا یہ مطلب ہو گاکہ جب زمین کی فریاد کو خدا پہنچے گا.یعنی لوگوں کے گناہوں اور شرک کی وجہ سے زمین اللہ تعالیٰ کے حضور فریاد کرے گی.کہ الٰہی میں گندی ہو گئی ہوں خراب ہو گئی ہوں.اور لوگوں نے اپنے گناہوں کی وجہ سے مجھے بگاڑ دیا ہے.پس جب آسمان پھٹے گا تو فرشتے اُتریں گے.اور زمین کی مدد کریں گے.گویا زمین کی پکار اور اس کی فریاد سنی جائے گی.لسان العرب میں جو معنی مَدَّ کے کئے گئے ہیں.اور جو حل لغات میں لکھے جا چکے ہیں.کہ مَدَّ کے معنی کھاد ڈالنے کے بھی ہوتے ہیں.ان کے اعتبار سے وَاِذَا الْاَرْضُ مُدَّتْ کے یہ معنی ہوں گے کہ زمین میں کھاد ڈالی جائے گی.اور خدا تعالیٰ روحانی ترقیات کے ابھرنے کے نئے سامان کرے گا.اسی طرح حل لغات میں لکھا گیا ہے کہ مَدَّالسَّرَاجَ بِالسَّلِیْطِ کے معنی ہوتے ہیں کہ صَبَّ فِیْہِ زَیْتًا.اس نے دیئے میں تیل ڈالا.تیل ڈالنے کے معنی حیات کے بھی لئے جا سکتے ہیں.اور دوبارہ قابلیتوں کے پیدا کرنے کے بھی لئے جا سکتے ہیں.اِس لحاظ سے وَاِذَا الْاَرْضُ مُدَّتْ کا یہ مطلب ہو گا کہ زمین میں نئی قابلیتیں پیدا کر دی جائیں گی.غرض اِ س آیت کے معنی یہ ہیں کہ زمین کو نئی عمر دی جائے گی.اس کی ہلاکت کو اللہ تعالیٰ کے پیچھے ڈال دے گا.اور اس میں نئی کھاد ڈالے گا.تاکہ وُہ ترقی کرے.وَ اَلْقَتْ مَا فِيْهَا وَ تَخَلَّتْۙ۰۰۵ اور جو کچھ اس میں ہے اس کو نکال پھینکے گی.اور خالی ہو جائے گی.حَلّ لُغَات.تَخَلَّتْ تَخَلَّتْ تَخَلّٰی سے مؤنث کا صیغہ ہے اور تَخَلّٰی مِنْہٗ وَعَنْہٗ کے معنی ہوتے ہیں تَرَکَہٗ اس کو چھوڑ دیا.اور تَخَلّٰی لَہٗ کے معنی ہوتے ہیں تَفَرَّغَ لَہٗ کسی کے لئے فارغ ہو گیا(اقرب).پس تَـخَلَّتْ کے معنی ہوں گے وہ چھوڑ دے گی یا الگ کر دے گی.تفسیر.وَ اَلْقَتْ مَا فِيْهَا وَ تَخَلَّتْسے مراد مامور کی جماعت اِس آیت کے معنی ایک تو یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس مامور کو جس کے لئے آسمان پھٹے گا.اور فرشتے آسمان سے اُتریں گے.ایسی جماعت عطا
Page 490
فرمائے گا جو قربانی کرنے والی ہو گی اور قربانی بھی معمولی نہیں بلکہ اَلْقَتْ مَافِیْھَا وَ تَخَلَّتْ اپنے مال اور اپنی جان اور اپنی عزت اور اپنے وطن اور اپنے آرام اور اپنے جذبات غرض ہر چیز کی وہ انتہائی طور پر قربانی کرنے والی ہو گی.اور خدا تعالیٰ کی راہ میں کسی بڑی سے بڑی قربانی سے بھی دریغ نہیں کرے گی.چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے جو جماعت عطا فرمائی وہ ایسی ہی ہے.آپ تحریر فرماتے ہیں.’’اِس زمانہ میں جس میں ہماری جماعت پیدا کی گئی ہے کئی وجوہ سے اس جماعت کو صحابہ رضی اللہ عنہم سے مشابہت ہے.وہ معجزات اور نشانوں کو دیکھتے ہیں جیسا کہ صحابہؓ نے دیکھا.وہ خدا تعالیٰ کے نشانوں اور تازہ بتازہ تائیدات سے نور اور یقین پاتے ہیں.جیسا کہ صحابہؓ نے پایا.وُہ خدا کی راہ میں لوگوں کے ٹھٹھے اور ہنسی اور لعن طعن اور طرح طرح کی دل آزاری اور بدزبانی اور قطع رحم وغیرہ کا صدمہ اٹھا رہے ہیں جیسا کہ صحابہؓ نے اٹھایا.وُہ خدا کے کھلے کھلے نشانوں اور آسمانی مددوںاور حکمت کی تعلیم سے پاک زندگی حاصل کرتے جاتے ہیں.جیسا کہ صحابہؓ نے حاصل کی.بہتیرے ان میں سے ہیں کہ نماز میں روتے اور سجدگاہوں کو آنسوئوں سے تر کرتے ہیں.جیسا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم روتے تھے.بہتیرے ان میں سے ایسے ہیں.جن کو سچی خوابیں آتی ہیں.اور الہام الٰہی سے مشرف ہوتے ہیں.جیسا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم ہوتے تھے.بہتیرے ان میں سے ایسے ہیں.کہ اپنے محنت سے کمائے ہوئے مالوں کو محض خدا تعالیٰ کی مرضات کے لئے ہمارے سلسلہ میں خرچ کرتے ہیں.جیسا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم خرچ کرتے تھے.ان میں ایسے لوگ کئی پائو گے کہ جو موت کو یاد رکھتے اور دلوں کے نرم اور سچی تقویٰ پر قدم مار رہے ہیں.جیسا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی سیرت تھی.وہ خدا کا گروہ ہے جن کو خدا آپ سنبھال رہا ہے.اور دن بدن ان کے دلوں کو پاک کر رہا ہے.اور ان کے سینوں کو ایمانی حکمتوں سے بھر رہا ہے.اور آسمانی نشانوں سے ان کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے.جیسا کہ صحابہؓ کو کھینچتا تھا غرض اِ س جماعت میں وہ ساری علامتیں پائی جاتی ہیں جو اٰخَرِیْنَ مِنْھُمْ کے لفظ سے مفہوم ہو رہی ہیں.اور ضرور تھا کہ خدا تعالیٰ کا فرمودہ ایک دن پُورا ہوتا.‘‘ (ایام الصلح روحانی خزائن جلد ۱۴ صفحہ ۳۰۶.۳۰۷) اِسی طرح فرماتے ہیں.’’مَیں دیکھتا ہوں کہ میری جماعت نے جس قدر نیکی اور صلاحیت میں ترقی کی ہے.یہ بھی ایک
Page 491
معجز ہ ہے.ہزارہا آدمی دل سے فدا ہیں.اگر آج ان کو کہا جائے کہ اپنے تمام اموال سے دست بردار ہو جائو.تو وہ دستبردار ہو جانے کے لئے مستعد ہیں.پھر بھی مَیں ہمیشہ ان کو اور ترقیات کے لئے ترغیب دیتا ہوں.اور ان کی نیکیاں ان کو نہیں سناتا.مگر دل میں خوش ہوں.(الذکر الحکیم نمبر ۴ صفحہ ۱۶،۱۷.۲۴؍ مئی ۱۸۹۶) اَلْقَتْ مَا فِيْهَا وَ تَخَلَّتْ کے پانچ معانی غرض اَلْقَتْ مَافِیْھَا وَتَخَلَّتْ کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس زمانہ کے مامور کو ایسی جماعت عطا فرمائے گا.جو خدا اور اس کے رسول کے لئے ان تمام چیزوں کو پھینک دے گی جو اس کے پاس ہوں گی اور خالی ہو جائے گی.اَلْقَتْ مَافِیْھَا وَتَخَلَّتْ کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ لوگ اپنی اندرونی قابلیتوں سے پورا پورا کام لیں گے اسی طرح اَلْقَتْ مَافِیْھَا وَتَخَلَّتْ سے یہ بھی مراد ہے کہ نفوس پاکیز ہ اس دن کلامِ الٰہی کو سننے کے لئے تیار ہو جائیں گے.اور آسمانی بارش اس پر نازل ہو گی.اور دلوں کو اس طرح تیار کر دیا جائے گا جس طرح زمین کو کھاد ڈال کر ہل چلا کر اور سہاگہ دے کر درست کیا جاتا ہے.کیونکہ مُدَّتْ میں یہ سب امور شامل ہیں.اِسی طرح ان الفاظ میں اس امر کی طرف بھی اشارہ تھا کہ تمام روحانی اور جسمانی علوم کو زمین باہر نکال دے گی.اور کوئی چیز مخفی نہیں رہے گی.گویا اس زمانہ میں روحانی اور جسمانی علوم کا ایسا اجتماع ہو گا جس کی مثال پہلے کسی زمانہ میں نہیں ملے گی.پس اَلْقَتْ مَافِیْھَا وَتَخَلَّتْ کے معنی یہ ہوئے کہ زمین اس زمانہ میں اپنے سارے خزانے اگل دے گی.یعنی وُہ وقت علوم کی ترقی کا ہو گا.اور علومِ آسمانی اور علومِ زمینی دونوں کا اس زمانہ میں مکمل ظہور ہو گا.ظاہری لحاظ سے اس کے یہ معنی ہوں گے.کہ زمین میں ایسے تغیرات ہوں گے.کہ جو کچھ اس میں ہو گا.وُہ اسے باہر پھینکنا شروع کر دے گی.چنانچہ پٹرول.مٹی کا تیل ہزاروں قسم کی دوائیں ویزیلین.گلیسرین.ریڈیم اور کئی قسم کی دھاتیں اور دوسری قابل استعمال اشیاء زمین میں سے ہی نکلی ہیں.گویا اِس آیت میں بتایا گیا ہے.کہ وہ زمانہ ایسا ہو گا.کہ اِدھر آسمان سب کچھ پھینک دے گا.اور ادھر زمین جو کچھ اس میں ہو گا نکال کر باہر پھینک دے گی.یہی مضمون دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے کہ اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَھَا وَاَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَثْقَالَھَا (الزلز ال:۲،۳ ) یعنی ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے جب زمین کو خوب جھنجوڑا جائے گا اور وُہ اپنے تمام بوجھوں کو نکال کر خالی ہو جائے گی.اَلْقَتْ مَافِیْھَا وَتَخَلَّتْ کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ زمین اپنے گناہوںکا کفارہ ادا کرے گی یعنی جو کچھ گند اس
Page 492
میں مخفی ہو گا وہ سب پھینک دے گی.نیکیوں میں ترقی کرے گی.گناہوں سے بیزار ہو جائے گی.اور آسمانی مدد اور نصرت کی وجہ سے اس کی ایسی اصلاح ہو جائے گی کہ زمین میں جس قدر نقائص پائے جاتے ہیں سب پھینک کر وہ خالی ہو جائے گی.وَ اَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَ حُقَّتْؕ۰۰۶ اور اپنے رب (کی بات سننے) کے لئے کان دھرے گی.اور یہی (اس پر)فرض ہے.تفسیر.یہ کفر والی زمین کا ذکر نہیں بلکہ ایمان والی زمین کا ذکر ہے کہ وہ اپنے رب کے لئے کان رکھے گی خالی استماع اور چیز ہے اور اس میں اتنی توجہ نہیں پائی جاتی جتنی توجہ اس شخص کے اندر ہوتی ہے جو کان لگا کر بیٹھا ہوا ہو کہ کوئی بات رہ نہ جائے.پس فرماتا ہے وہ زمین اپنے رب کی باتیں سننے کے لئے کان لگائے بیٹھی رہے گی وَحُقَّتْ اور یہ زمین ہے ہی اس قابل یعنی ہم زمین میں بھی ایسی قابلیت پیدا کر دیں گے کہ خدا تعالیٰ کی کامل فرمانبرداری اور اطاعت کا مادہ اس میں پیدا ہوجائے گا.يٰۤاَيُّهَا الْاِنْسَانُ اِنَّكَ كَادِحٌ اِلٰى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلٰقِيْهِۚ۰۰۷ اے انسان تو اپنے رب کی طرف پورا زور لگا کر جانے والا ہے.(اور) پھر اس سے ملنے والا ہے.حَلّ لُغَات.کَادِحٌ کَادِحٌ کَدَحَ سے اسم فاعل کا صیغہ ہے اور کَدَحَ کے معنی ہوتے ہیں پوری محنت کرنا.ایسی محنت کرنا جس کا جسم پر اثر پڑ جائے.کہتے ہیں کَدَحَ (یَکْدَحُ کَدْحًا) اَیْ سَعٰی وَعَمِلَ لِنَفْسِہٖ خَیْرًا اَوْ شَرًّا وَکَدَّ.اس نے کام کرنے کی کوشش کی.چاہے وہ کوشش اچھی تھی یا بُری.اور خوب محنت سے کام لیا وَقِیْلَ اَلْکَدْحُ جُھْدُ النَّفْسِ فِی الْعَمَلِ وَالْکَدُّ فِیْہِ حَتّٰی یُؤَثِّرَ فِیْھَا.بعض لغوی کہتے ہیں کہ کدح اس کام کو کہتے ہیں.جو اتنی محنت سے کیا جائے کہ انسان کی صحت برباد ہو جائے.اس کی ہڈیاں گھل جائیں اور اس کے جسم کے اندر تک اثر پہونچ جائے.(اقرب) پس کَادِحٌ کے معنی ہوں گے.پوری محنت ومشقت کرنے والا.تفسیر.فرماتا ہے اے انسان تو پوری جدوجہد کرے گا.پوری محنت کرے گا اپنے رب کی طرف جانے کی فَمُلٰقِيْهِ اور آخر تو اس سے جا کر مل ہی جائے گا.
Page 493
خدا کو پانے کے لئے انتہائی محنت کی ضرورت یہاں يٰۤاَيُّهَا الْاِنْسَانُ میں یا تو عام قاعدہ بیان کیا گیا ہے.اور یا اس سے مراد صرف وقت کا امام ہے یعنی یا تو اس سے یہ مراد ہے.کہ اے انسان تیرے لئے اپنے رب سے ملنے کا رستہ کھلا ہے.شرط یہ ہے کہ تیری طرف سے کدح ہونا چاہیے.اِ ن معنوں کے لحاظ سے ہر انسا ن اِس میںشامل ہے.اور یا پھر ہر انسان براہ راست اس میں شامل نہیں.بلکہ کامل انسان کے تابع ہو کر شامل ہے.اور معنی یہ ہیں کہ اے کامل انسان تُو اپنے رب کو پانے کے لئے بڑی قربانیاں کرے گا.اور آخر ایک دن اس کو پا ہی لے گا.اور جب کوئی کامل انسان اس کو پا لیتا ہے.تو پھر سب کو حکم ہو جاتا ہے کہ تم بھی اِسی راستہ پر چلو.اور خدا تعالیٰ کا قرب حاصل کر لو.اِ س آیت میں بتایا گیا ہے کہ خدا تعالیٰ کے رستے کا ملنا معمولی بات نہیں ہوتی.اِس غرض کے لئے انسان کو اتنی محنت کرنی پڑتی ہے کہ اس کی ہڈیوں تک اثر پہونچ جاتا ہے.یہی وُہ نکتہ ہے جس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگ لقاء الٰہی سے محروم رہ جاتے ہیں.وہ سمجھتے ہیں کہ جب انہیں ایمان نصیب ہو گیا.تو کچھ دیر بیٹھ کر ایمان کی باتوں کا مزہ لے لینے اور نمازروزہ وغیرہ ادا کر لینے سے ہی ان کی روحانیت کامل ہو جائے گی.حالانکہ روحانیت کامل ہوتی ہے اس غم کی وجہ سے جو عشق سے پیدا ہوتا ہے جس کے اثر سے انسان کی ہڈیاں تک گھل جاتی ہیں.جب تک انسان کے دل میں خدا تعالیٰ کے متعلق یہ رغبت پیدا نہ ہو.یہ غم پیدا نہ ہو.یہ عشق اور محبت پیدا نہ ہو.اس وقت تک مُلَاقِیْہِ کا مقام اسے میسر نہیں آ سکتا.باقی نماز پڑھ لینا یا روزے رکھ کر یہ سمجھ لینا کہ میں نے بڑی مشقت برداشت کر لی ہے.ایسی باتیں نہیں ہیں.جو کدح میں شامل ہوں.اِس سے بہت زیادہ مشقت طلب کام لوگ کرتے ہیں.چوڑھوں کو دیکھ لو وہ کتنی محنت کرتے ہیں.دھوبیوں کو دیکھ لو وہ کس قدر مشقت کا کام کرتے ہیں.سقوں کو دیکھ لو.وہ کس قدر تکلیف برداشت کرتے ہیں مگر یہ نہیں ہوتا کہ اس کام سے ان کی ہڈیاں گھلنی شروع ہو جائیں.کام کا جتنا اثر ہوتا ہے صرف جسم پر ہوتا ہے جو کچھ دیر کے بعد زائل ہو جاتا ہے.لیکن یہاں اللہ تعالیٰ کَادِحٌ کا لفظ استعمال فرماتا ہے اور کدح اس بات کو کہتے ہیں کہ انسان ایسا عمل کرے کہ یوں معلوم ہو اس کی صحت بگڑ جائے گی.اس کی ہڈیاں گھل جائیںگی.اور اس کا جسم تباہ ہو جائے گا.جب انسان اس رنگ میں کام کرتا ہے.تب اسے کامیابی حاصل ہوتی ہے اس کے بغیر اس کا اپنی کامیابی کے متعلق امید رکھنا غلطی ہوتی ہے.میں نے اپنی جماعت میں خدام الاحمدیہ اور انصاراللہ کو اِسی غرض کے لئے قائم کیا ہے کہ وہ محنت کریں اور مشقت طلب کاموں کی اپنے اندر عادت پیدا کریں جب تک انسان اپنے اوقات کو ضائع ہونے سے نہیں بچاتا اسے خدا نہیں مل سکتا.خدام الاحمدیہ اور انصاراللہ کے
Page 494
قیام کا اصل مقصد یہ ہے کہ جماعت میں مشقت طلب کاموں کی عادت پیدا ہو.اور ہر فرد کسی نہ کسی کام میں مشغول رہے.پس يٰۤاَيُّهَا الْاِنْسَانُ اِنَّكَ كَادِحٌ اِلٰى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلٰقِيْهِ میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب تک ہر انسان اپنے آپ کوکام کرتے کرتے فنا نہیں کر دیتا.اس وقت تک قومی طور پر خدا نظر نہیں آ سکتا.انفرادی طور پر بے شک کدح کے بعد انسان کو لقاء الٰہی حاصل ہو جاتا ہے.مگر قومی طور پر اسی وقت لقاء الٰہی کی نعمت حاصل ہوتی ہے جب قوم کا ہر فرد اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے.دنیا میں لقاء الٰہی د و طرح حاصل ہوتا ہے.ایک فردی طور پر اور ایک قومی طور پر.اگر قوم تباہ بھی ہو چکی ہو تب بھی فردی طور پر انسان خدا تعالیٰ کا قُرب حاصل کر سکتا ہے.جیسے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بعثت سے قبل باوجود اس کے کہ مسلمان قومی طور پر تباہ وبربادہو چکے تھے.ان میں بعض بزرگ پائے جاتے تھے.مثلًا حضرت عبداللہ غزنوی کے متعلق خود حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے لکھا ہے کہ وہ بزرگ انسان تھے(حقیقۃ الوحی روحانی خزائن جلد ۲۲ صفحہ ۲۵۰).اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام سے پہلے حضرت مجدد صاحب بریلوی یا حضرت مولوی محمد اسماعیل صاحب شہید اور اسی طرح بعض اور بزرگ گزرے ہیں.مگر یہ چالیس کروڑ مسلمانوں میں سے چند نفوس تھے.جو خدا تعالیٰ سے ملے اِن لوگوں کو خدا تعالیٰ نے یہ دکھانے کے لئے بھیجا تھا کہ اسلام اب بھی اپنے اندر طاقت رکھتا ہے اور اب بھی وہ لوگوں کو زندہ کر سکتا ہے.اب بھی وہ انہیں خدا تعالیٰ کے دربار تک پہنچا سکتا ہے.مگر قومی طور پر ان کے وجود سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا.پس حضرت سید احمد صاحب بریلوی کیا تھے.وہ درحقیقت حُجّت تھے سستوں پر.وہ حجّت تھے غافلوں پر اور وہ یہ بتانے کے لئے بھیجے گئے تھے کہ اسلام اب بھی اپنے اندر زندگی بخش اثرات رکھتا ہے.اسی طرح حضرت سید اسمٰعیل صاحب شہیدؓ کیا تھے وہ حجّت تھے سستوں پر.وہ ججّت تھے غافلوں پر.اور وہ یہ بتانے کے لئے بھیجے گئے تھے کہ اسلام اب بھی اپنے اندر زندگی بخش اثرات رکھتا ہے.مگر بحیثیت قوم اسلام کو ان کے وجود سے کوئی خاص فائدہ نہیں پہنچا.کیونکہ اسلام نام تھا چالیس کروڑ افراد کا جن میں سے کوئی چین میں رہتے تھے کوئی جاپان میںرہتے تھے.کوئی سماٹرا اور جاوا میں رہتے تھے.اور کوئی دوسرے ممالک میں رہتے تھے اور یہ وہ ممالک ہیں جہاں ان لوگوں کی کوئی آواز نہیں پہنچی.یوں ہماری جماعت بھی ابھی چھوٹی سی ہے.مگرہماری جماعت وُہ ہے جو خدا تعالیٰ کے فضل سے مختلف ممالک میں پھیل رہی ہے پس وہ لوگ صرف غافلوں پر حجت تھے.اور اس بات کی دلیل تھے کہ خدا اب بھی لوگوں کو زندہ کر سکتا ہے.ورنہ ان کے زمانہ میں قومی طور پر مسلمانوں نے خدا تعالیٰ کے چہرہ کو نہیں دیکھا.
Page 495
پس يٰۤاَيُّهَا الْاِنْسَانُ اِنَّكَ كَادِحٌ اِلٰى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلٰقِيْهِ اے جماعتِ مومنین کے ہر فرد تم میں سے ہر شخص کو اس راستہ میں اپنے آپ کو فنا کر دینا پڑے گا.تب تمہیں قومی طور پر خدا تعالیٰ کا چہرہ نظر آئے گا.اور اس کے لقاء کی نعمت تمہیں میسّر آئے گی.اور یہی نعمت حقیقی نعمت ہوتی ہے.ورنہ انفرادی طور پر توہر زمانہ میں لوگ خدا تعالیٰ کو پاتے رہتے ہیں.لیکن انفرادی طور پر خدا تعالیٰ کو پا لینے سے قوم کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا.قومی طور پر اسی وقت خدا تعالیٰ کا جلال ظاہر ہوتا ہے اور قوم کا ہر فرد خدا تعالیٰ کا چہرہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے.جب ہر فرد اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کےقرب کے راستوں میں فنا کر دیتا ہے.اور اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹتا.جب تک اِس نعمتِ عظیمہ کو حاصل نہیں کر لیتا.مُلٰقِيْهِ میں ضمیر جزاء کی طرف بھی جا سکتی ہے مُلٰقِيْهِ کی ضمیر جزا کی طرف بھی جا سکتی ہے.مگرجو معنی اس وقت مَیں کر رہا ہوں.اس لحاظ سے خدا کا ملنا زیادہ موزوں معلوم ہوتا ہے.گو جزا کی طرف بھی اس کی ضمیر جا سکتی ہے.فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتٰبَهٗ بِيَمِيْنِهٖۙ۰۰۸فَسَوْفَ يُحَاسَبُ پس جس کے داہنے ہاتھ میں اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا.اس سے تو جلد ہی آسان حساب لے لیا جائے گا.حِسَابًا يَّسِيْرًاۙ۰۰۹وَّ يَنْقَلِبُ اِلٰۤى اَهْلِهٖ مَسْرُوْرًاؕ۰۰۱۰ اور وُہ اپنے اہل کی طرف خوش (بخوش) لوٹے گا.تفسیر.دائیں ہاتھ میں کتاب دئیے جانے سے مراد کام کرنے کے لئے ہمیشہ دایاں ہاتھ استعمال کیا جاتا ہے.چونکہ پچھلی آیت میں کدح کا لفظ استعمال فرمایا تھا.اس لئے یہاں یہ بتایا کہ ساری ترقی دائیں ہاتھ کے چلانے میں ہے.اگر تم دایاں ہاتھ چلاتے جائو گے تو جیت جائو گے.ان دو آیات میں ساری تحریک جدید کا خلاصہ بیان کر دیا گیا ہے.کہ محنت و مشقت برداشت کرنا اور ہاتھ سے کام کرنے کا عادی ہوناانسان کو اپنی زندگی میں کامیاب بنا دیتا ہے.فَسَوْفَ یُحَاسَبُ حِسَابًا یَّسِیْرًا کے یہی معنی ہیں کہ اس شخص کا حساب آسان لیا جائے گا.یعنی مشکلات اور تکالیف کے آنے پر وہ کوئی گھبراہٹ محسوس نہیں کرے گا.کیونکہ مشقت برداشت کرتے کرتے وہ ان چیزوں کا عادی ہو چکا ہو گا اور اسے مشکلات بھی آسان معلوم ہوں گی.جو شخص نکمّا سست اور عیاش ہو وہ ذرا سی
Page 496
مصیبت پر بھی گھبرا جاتا ہے لیکن جو شخص محنتی ہو اور مشقت برداشت کرنے کا عادی ہو.اس پر خواہ مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ پڑے.وُہ اس کو آسانی سے برداشت کر لیتا ہے.اس آیت کے یہ معنی بھی ہیں کہ خدا ایسے مومن سے آسان معاملہ کرے گا.مگر اس کے یہ معنی بھی ہیں کہ وُہ خواہ کس مصیبت میں ڈالا جائے.وہ اسے آسان معلوم ہو گی.جن لوگوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کے لئے اپنا وطن چھوڑا.اپنی عزت چھوڑی اپنا مال چھوڑا.اپنے بیوی بچے چھوڑے.ان کو بعد میں کون سی ایسی مصیبتیں پیش آئی تھیں.جنہوں نے ان کو دکھ میں ڈال دیا ہو.بعد میں جو بھی مصیبت آئی.وُہ انہیں بالکل آسان معلوم ہوئی.اور اسے انہوں نے ہنسی خوشی برداشت کر لیا.غالبؔ شرابی تھا.لیکن اس کی زبان پر حکمت کی بہت سی باتیں جاری ہوئیں ہیں معلوم ہوتا ہے اس کے دل میں ضرور نیکی تھی.وہ ایک مقام پر کہتا ہے ع مشکلیں مجھ پر پڑیں اتنی کہ آسان ہو گئیں (دیوان غالب صفحہ ۱۱۰ ) جب انسان اپنے آپ کو تنعّم اور عیش کا عادی بنا لے تو جو حساب بھی آتا ہے.اسے سخت معلوم ہوتا ہے.لیکن اگر شدائد برداشت کرنے کا انسان عادی بن جائے تو پھر اسے حساب آسان نظر آتا ہے.دو قسم کے ابتلاء حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ دو قسم کے ابتلاء ہوتے ہیں.ایک ابتلاء وہ ہوتا ہے.جس میں بندے کو اختیار ہوتا ہے.کہ وہ اس کے متعلق اگر کوئی آرام اور سہولت کا پہلو تلاش کر سکتا ہو تو کر لے لیکن ایک ابتلاء وہ ہوتا ہے.جو خدا تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے اور جس میں سخت مشکل پیش آتی ہے.آپ فرمایا کرتے تھے.اس کی ایسی ہی مثال ہے.جیسے نماز کے لئے وضو کرنا پڑتا ہے.نماز کے لئے وضو کرنا ضروری ہوتا ہے.لیکن اگر سردی کا موسم ہو.تو انسان کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ اگر چاہے تو پانی کو گرم کر لے.یہ وہ ابتلاء ہے جس کے جاری کرنے کا اختیار اللہ تعالیٰ نے انسان کے اختیار میںدیا ہے.لیکن دوسری قسم کا ابتلاء جسے اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے.اس کے صدمہ کو آسان کرنا انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا.جیسے کہ کسی عزیز کی موت.ایسے صدمے تبھی برداشت ہو سکتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو تلخ زندگی کا عادی بنائے اور عیش و آرام کی زندگی کو چھوڑ دے.اور جب انسان ایسا کرلے تو اسے ہر چیز آسان معلوم ہوتی ہے.(ملفوظات جلد ۳ صفحہ ۶۳۸) وَ يَنْقَلِبُ اِلٰۤى اَهْلِهٖ مَسْرُوْرًا.اور وہ اپنے اہل کی طرف خوش خوش واپس آئے گا.یہ آیت بھی صاف طور پر بتا رہی ہے کہ اس میںدنیا کے حساب کا ہی ذکر ہو رہا ہے.کیونکہ اگلے جہان میں جب حساب ہو گا.اس وقت تو کسی کو
Page 497
اپنے اہل کا پتہ ہی نہیں ہو گا.کہ وہ کہاں ہے.پھر ضروری نہیں کہ اس کے اہل میں جتنے افراد ہوں وہ سارے جنتی ہوں.ہو سکتا ہے ان میں سے بعض دوزخی ہوں.لیکن یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے.کہ حساب کے بعد وہ اسی وقت اپنے اہل کی طرف جائے گا.اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ مومن مرد کے اہل وعیال کو بھی اس کے ساتھ ہی رکھے گا.مگر یہ بعد میں ہو گا.یہ نہیں کہ ادھر حساب ہو رہا ہو.اور ادھر اس کا اہل جنت میں اس کے ساتھ جانے کے لئے وہاں آن موجود ہو.وہاں تو ایسی کیفیت ہو گی.کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم نے مجھے وہاں تلاش کرنا ہو.تو اس اس نشان کے ذریعہ سے کرنا جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کی تلاش کے لئے علامتوں کی ضرورت ہو گی.تو ایک عام مومن کو اپنا اہل کس طرح فوراً مل سکے گا.پس يَنْقَلِبُ اِلٰۤى اَهْلِهٖ مَسْرُوْرًا کے الفاظ بتارہے ہیں کہ یہ اس دنیا کا واقعہ ہے یعنی دین کے لئے محنت کرنے والا محنت کرے گا.اور پھر اچھے نتائج حاصل کر کے اپنے اہل کے پاس خوش و خرم واپس آئے گا.وَ اَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتٰبَهٗ وَرَآءَ ظَهْرِهٖۙ۰۰۱۱فَسَوْفَ يَدْعُوْا اور جس کو اس کی پیٹھ کے پیچھے سےاس کا اعمال نامہ دیا جائے گا وہ جلد ہی (اپنے مونہہ سے اپنی)ہلاکت کو ثُبُوْرًاۙ۰۰۱۲وَّ يَصْلٰى سَعِيْرًاؕ۰۰۱۳ بلائے گا.اور بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہو گا.حَلّ لُغَات.اَلثَّبُوْرُ.الثَّبُوْرُ اَلْھَلَاکُ وَالْفَسَادُ یعنی ثبورکے معنے ہلاکت اور فساد کے ہیں.(مفردات) تفسیر.پیٹھ کے پیچھے سے کتاب دئیے جانے سے مراد وَ اَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتٰبَهٗ وَرَآءَ ظَهْرِهٖ.اس سے مراد وہ شخص ہے جو اپنے کام ہمیشہ پیچھے ڈالتا رہتا ہے کہتا ہے آج نہیں کل کروں گا.کل آتا ہے تو کہتا ہے پرسوں کروں گا.غرض وہ جواپنی پیٹھ کے پیچھے کام کو پھینکتا چلا جائے گا.اسے پیٹھ کے پیچھے سے کتاب دی جائے گی..جس نے دائیں ہاتھ کو کام میں لگائے رکھا تھا.اس کے تو دائیں ہاتھ میں کتاب دی جائے گی.لیکن جو روز بروز اپنے کام کو پیچھے ڈالتا چلا جائے گا.اسے پیٹھ کے پیچھے سے کتاب دی جائے گی.فَسَوْفَ یَدْعُوْا ثُبُوْرًا جس شخص کی پیٹھ کے پیچھے سے کتاب آئے گی.صاف بات ہے کہ اس کے لئے کوئی
Page 498
خوشی کی بات نہیں ہو سکتی.کیونکہ خوشی کی بات ظاہر کی جاتی ہے.اور رنج والی چیز چھپائی جاتی ہے.کیونکہ اس کے لئے بھی یہ بات رنج کا موجب ہو گی.اِس لئے اسے پیٹھ کے پیچھے سے کتا ب دی جائے گی.جسے دیکھ کر وہ جلد ی ہی اپنے لئے ہلاکت طلب کرے گا.یَدْعُوْا ثُبُوْرًا کے معنی ہیں یَدْعُوْا ثُبُوْرًا لِنَفْسِہٖ یعنی وہ اپنے نفس کے لئے ہلاکت طلب کرے گا.یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں کہ خدائی گرفت اتنی سخت ہو گی.کہ یَالَیْتَنِیْ کُنْتُ تُرَابًا والا نظارہ نظر آ جائے گا.اور وہ کہے گا کاش میں مر جائوں اور اس انجام کو نہ دیکھوں.یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ ہلاکت خدا نہیں بھیجتا بلکہ بندہ اپنے اعمال کی وجہ سے اس کاخود مورد بنتا ہے.پس عذاب دینے والا خدا نہیں بلکہ بندہ اپنے اعمال سے اس عذاب کو اپنی طرف بلاتا ہے.وَ يَصْلٰى سَعِیْرًا اور وہ ایک بھڑکنے والی آگ میں داخل ہو گا.دنیا کے لحاظ سے اس کے یہ معنی ہوں گے.کہ وُہ جلن اور فکر اور غم میں مبتلا کیا جائے گا اور آخرت کے لحاظ سے معنی ظاہر ہی ہیں.اِنَّهٗ كَانَ فِيْۤ اَهْلِهٖ مَسْرُوْرًاؕ۰۰۱۴ وہ اپنے اہل وعیال میں خوب خوش رہا کرتا تھا.تفسیر.فرماتا ہے یہ وُہ شخص ہے جو اپنے اہل میں بہت مسرور ہوا کرتا تھا.پہلی آیات میں آیا تھا کہ يَنْقَلِبُ اِلٰۤى اَهْلِهٖ مَسْرُوْرًا یعنی محنت اور کوشش اور کدح کی وجہ سے چونکہ مومن کو اپنے گھر میں آرام اور چین سے بیٹھنا نصیب نہیں ہوتا تھا.اس لئے جب اسے بدلہ ملے گا.تو يَنْقَلِبُ اِلٰۤى اَهْلِهٖ مَسْرُوْرًا وہ اپنے اہل کی طرف خوش خوش جائے گا.کہ میں کامیاب و بامراد واپس آ گیا.لیکن کافر چونکہ اپنے گھر میں عیش و آرام سے بیٹھا رہتا تھا.خدا تعالیٰ کی خوشنودی کے لئے کوئی کام نہ کرتا تھا.اس لئے جب نتیجہ نکلے گا.تو وہ سخت غمگین ہو گا.اس سے معلوم ہوا کہ مومن اپنے کام کو غم سے شروع کر تا اور خوشی پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے اور کافر خوشی سے شروع کرتااور غم پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے.
Page 499
اِنَّهٗ ظَنَّ اَنْ لَّنْ يَّحُوْرَۚۛ۰۰۱۵ (اور) یقین رکھتا تھا کہ فراخی کے بعد کبھی اسے تنگی نہ آئے گی.حَلّ لُغَات.حَارَ.حَارَ یَحُوْرُ (حَوْرًا وَحُؤُوْرًا) کے معنی ہوتے ہیں رَجَعَ واپس لوٹا.حَارَتِ الْفُصَّۃُ حَوْرًا کے معنی ہوتے ہیں اِنْحَدَرَتْ کَاَنَّھَا رَجَعَتْ مِنْ مَوْضِعِھَا گلے میں پھنسنے والی چیز نیچےاتر گئی.گویا اپنی جگہ سے ہٹ گئی اور حَارَ فَلَانٌ حَوْرًا کے معنی ہوتے ہیں.تَـحَیَّرَ وہ متحیر ہو گیا.اور عربی میں محاورہ ہے کہتے ہیں حَارَ بَعْدَ مَاکَارَ اسی طرح ایک روایت میں ہے.نَعُوْذُ بِاللّٰہِ مِنَ الْحَوْرِ بَعْدَ الْکَوْرِ اَیْ مِنَ النُّقْصَانِ بَعْدَ الزِّیَادَۃِ یعنی خوشی کے بعد غم.فائدہ کے بعد نقصان اور سکھ کے بعد دکھ سے ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں (اقرب) گویا حَوْرٌ کے معنی ہیں حالت کا بدلنا.پس اِنَّہٗ ظَنَّ اَنْ لَنْ یَّحُوْرَ کے یہ معنے ہوئے کہ وہ یہ خیال کرتا تھا وہ ہماری طرف لوٹ کر نہیں آئے گا.یا اس کی ا چھی حالت بُری حالت کی طر ف نہیں لوٹے گی.یا یہ کہ وہ کبھی بھی ایسی مشکلات سے دو چار نہیں ہو گا.کہ وہ متحیر ہو کر رہ جائے.یا یہ کہ اسے نقصان کبھی نہیں پہنونچے گا.تفسیر.اکثر تباہیاں دنیا میں اس خیال کے ماتحت آتی ہیں.کہ بہت لوگ جب ان کو کوئی کامیابی یاترقی یا بلندی حاصل ہوتی ہے.تو سمجھ لیتے ہیں.کہ اب اس کے بعد تنزل کی حالت کبھی نہیں آئے گی.جس کی وجہ سے وہ تنزّل سے بچنے کے لئے تیاری نہیں کرتے.قومیں ترقی کر جاتی ہیں.تو وُہ آئیندہ کے لئے تنزل کے رستے مسدود کرنے کی کوشش نہیں کرتیں.نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب تنزل کا وقت آتا ہے.تو پھر انہیں واپس لوٹنے کا موقعہ نہیں ملتا.الٰہی قانون یہی ہے کہ جس جہت پر گاڑی چل رہی ہو سٹیم کے ختم ہونے کے بعد بھی کچھ دیر گاڑی اسی طرف چلتی رہتی ہے اور یہی چیز قوموں کے دھوکے کا موجب ہوجاتی ہے.اگر قومی سٹیم کے ختم ہوتے ہی یکدم ترقی کی گاڑی رک جائے.تو علاج کی طرف توجہ پیدا ہو جائے لیکن سٹیم بند ہو جاتی ہے اور گاڑی چلتی رہتی ہے.نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس وقت قومی بربادی کا احساس ہوتا ہے.جب اس کا علاج ناممکن ہو جاتا ہے.بَلٰۤى١ۛۚ اِنَّ رَبَّهٗ كَانَ بِهٖ بَصِيْرًاؕ۰۰۱۶ مگر ایسا تو (ضرور) ہونا تھا.کیونکہ اس کا رب اسے یقیناً دیکھ رہا تھا.تفسیر.فرماتا ہے ایسے انسان کا یہ خیال درست نہیں حقیقت تو اس کے خلاف ہے.یقیناً اس کا رب اس کو
Page 500
اچھی طرح سے دیکھ رہا تھا.یعنی ہر عمل انسان کا اور ہر عمل قوم کا خدا کی نگاہ کے نیچے ہوتا ہے.جب وہ عمل اسے بھولا ہوا ہوتا ہے.خدا کو وہ یاد ہوتا ہے.اس لئے خواہ قومی اعمال پر کتنا ہی پردہ پڑا ہوا ہو.نتیجہ حقیقت کے مطابق نکلتا ہے.کبھی خلاف نہیں نکلتا.فرماتا ہے ان لوگوں کے لئے بھی ایک دن تنزل کے سامان پیدا ہو جائیں گے.یہاں وُہ لوگ مراد ہیں.جو اس زمانہ کے ظہور کے مقابل پر کھڑے ہوں گے.اور یہ بتایا گیا ہے کہ بظاہر اِس آسمانی اور زمینی تبدیلی کے وقت کفر طاقتور ہو گا.اور دیکھنے والے یہی سمجھیں گے کہ کفر مغلوب نہیں ہو سکتا.مگر اندرونی طور پر اس میں ایسی تبدیلیاں پیدا ہو چکی ہوں گی.کہ وُہ آسمانی نظام کے مقابلہ میں ٹھہر نہیں سکے گا.فَلَاۤ اُقْسِمُ بِالشَّفَقِۙ۰۰۱۷ پس یوں نہیں (جو یہ سمجھتے ہیں بلکہ) میں شہادت کے طور پر پیش کرتا ہوں سورج کے غروب ہونے کے بعدکی سرخی کو وَ الَّيْلِ وَ مَا وَسَقَۙ۰۰۱۸وَ الْقَمَرِ اِذَا اتَّسَقَۙ۰۰۱۹ اور رات کو بھی اور اسے بھی جسے وہ سمیٹ لیتی ہے.اور چاند کو (بھی) جب وُہ تیرھویں کا ہو جائے.حَلّ لُغَات.لَاۤ اُقْسِمُ میں لفظ لا کے متعلق بحث یہاں جو لا آیا ہے اس کے متعلق نحویوں میں اختلا ف ہے.ابوعبیدہ اور ایک جماعت مفسرین کی کہتی ہے.کہ یہ لا زائدہ ہے.اور مراد یہی ہے کہ اُقْسِمُ بِالشَّفَقِ یعنی میں شفق کو بطور شہادت پیش کرتا ہوں لا کے استعمال کے متعلق ادیبوں میں اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ یہ ایسے موقعہ پر زائد استعمال ہوتا ہے.اور زَیَادَتُھَا جَارِیَۃٌ فِیْ کَلَامِ الْعَرَبِ.اس کی یہ زیادت کلام عرب میں عام رائج ہے.چنانچہ وہ مثال کے طور پر قرآن کریم کی ان دو آیات کو پیش کرتے ہیں.(۱)مَامَنَعَکَ اَلَّا تَسْجُدَ (اعراف:۱۳)تجھے کس نے منع کیا کہ سجدہ نہ کرے حالانکہ یہاں مراد یہ ہے کہ تو سجدہ کرے (۲)اسی طرح آتا ہے لِئَلَّا یَعْلَمَ اَھْلُ الْکِتٰبِ(الحدید:۳۰)تاکہ اہل کتاب کو معلوم نہ ہو حالانکہ مراد یہ ہے کہ اہل کتاب کو معلوم ہو ساتھ ہی یہ لوگ کہتے ہیں.اِنَّمَا تَزَّادُ فِیْ وَسْطِ الْکَلَامِ لَا فِیْ اَوَّلِہٖ یعنی لا درمیان کلام میں زائد آتا ہے.ابتدا کلام میں زائد نہیں آتا.مگر بعض مفسرین اس کے بارہ میں یہ کہتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کے کلام پر یہ قاعدہ لگتا ہے.قرآن کریم پر نہیں لگتا.کیونکہ سب قرآن ایک ہی سورۃ کے حکم میں ہے.اِس لئے جہاں بھی لا آئے گا وسط کلام ہی سمجھا جائے گا.اس پر معترضین نے یہ کہا ہے کہ مضمون کے لحاظ سے بیشک سارا قرآن کریم ایک ہی حکم میں ہے مگر
Page 501
عبارت ظاہر ی کے لحاظ سے اس کی آیات الگ الگ ہیں.پس عبارت ظاہری کے لحاظ سے ایک سورۃ کو دوسری سورۃ کا حصہ نہیں سمجھا جا سکتا.اگر اس اعتراض کو درست تسلیم کر لیا جائے.تو لا کے اس استعمال پر جو سورتوں کے شروع میں ہوا ہے اعتراض پڑے گا.مگر ان قسموں پر اعتراض نہیں پڑ سکتا.جو درمیان میں آجاتی ہیں.جیسے یہاں ہے.(تفسیر فتح البیان زیر آیت لا اقسم بیوم القیامۃ) اِس جگہ یہ بات مدنظر رکھنی چاہیے کہ اس خلش کی بنیاد ایک ذہنی وسوسہ پر ہے.اور وہ یہ کہ لا کو نافیہ سمجھا گیا ہے.لا نافیہ کی صورت میں ہمیں بے شک اس بات کی احتیاج ہے.کہ اس سے پہلے کوئی مضمون نکالیں جس کی نفی لا کرتا ہو.لیکن زائدہ کی صورت میں یہ سوال کہ ابتداء میں آیا ہے.عقلی طور پر درست معلوم نہیں ہوتا.کشاف میں لکھا ہے کہ لا نافیہ کا استعمال قسم سے پہلے عربوں کے کلام اور شعروں میں عام ہے اور اس کا مقصد مضمون قسم کی تاکید کرنا ہوتاہے.بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ھِیَ رَدٌّ لِکَلَامِھِمْ وَعَقِیْدَتِھِمْ کَاَنَّہُ قِیْلَ لَیْسَ الْاَمْرُ کَمَا ذَکَرْتُمْ اُقْسِمُ بِکَذَا وَکَذَا (فتح القدیر للشوکانی سورۃ القیامۃ آیات ۱ تا ۱۵)یعنی لاء نفی کے معنوں میں ہی آیا ہے.اور مخالف کے کلام اور اس کے عقیدہ کی تردید میں آیا ہے.اور مفہوم یہ ہے کہ جس طرح تم کہتے ہو اس طرح معاملہ نہیں.میں اپنی بات کی شہادت کے لئے فلاں بات پیش کرتا ہوں.چنانچہ فرّاء اور اکثر نحویوں کا قول ہے کہ یہ لا زائدہ نہیں بلکہ نافیہ ہے.اور وہ اس کی مثال بھی دیتے ہیں کہ عام عربی بول چال میں کہتے ہیں لَا وَاللّٰہِ ا ور جب وہ یہ الفاظ کہتے ہیں تو یہ معنی نہیںہوتے.کہ میں اللہ کی قسم نہیں کھاتا بلکہ اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ مَیں تمہاری بات ردّ کرتا ہوں.اور اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں.کہ میری بات سچی ہے بعض کہتے ہیں کہ ہوتا تو نفی کے لئے ہے.لیکن ضروری نہیں کہ مضمونِ قسم کی نفی کے لئے ہو.بلکہ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس چیز کی قسم کھا کر میں اس کا پورا حق ادا نہیں کرتا.اور اس کی پوری عظمت ظاہر نہیں کرتا.ظاہر ہے کہ یہ معنی خواہ کتنے بڑے آدمی نے کئے ہوں.بہرحال لغو اور غلط ہیں.کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ کی قسموں کا ذکر ہے.پس یہ معنی کرنے کہ خدا فرماتا ہے میں قسم تو کھاتا ہوں پرقسم کا حق ادا نہیں کر سکتا.ایک کھلی ہوئی غلطی ہے.الحمدللہ کے مستحق وجود کے متعلق یہ کہنا کہ وہ حق اد ا نہیں کر سکتا کس طرح درست ہو سکتا ہے.بعض نے کہا ہےکہ نفیِ قسم ہی مراد ہے.اور مراد یہ ہے کہ مَیں اس چیز کی قسم نہیں کھاتا.اور مقدر یہ مضمون ہوتا ہے.کہ یہ امر ظاہر ہے.اور اس پر کسی قسم کی ضرورت نہیں ہے.لیکن یہ معنی بالبداہت باطل ہیں.(فتح القدیر للشوکانی سورۃ القیامۃ آیات ۱ تا ۱۵) کیونکہ جس امر کو ظاہر کرنا ہے وہ مقسم علیہ ہے.اور وہی مطلوب ہے اور جس چیز کی قسم کھانی ہے.وہ تو گواہ ہے.اور یہ کہنا کہ مَیں تو اس کی قسم نہیں
Page 502
کھاتا.اور مراد یہ لینا کہ میں تو اس کی گواہی نہیں دلاتا.کیونکہ اس کی گواہی ظاہر ہے.ایک بے معنی فقرہ ہو جاتا ہے.پس حقیقت یہی ہے کہ یہاں لا زائدہ ہے.یعنی تاکید کے لئے آیا ہے اور محاورۂ عرب کے عین مطابق ہے اور اس بارہ میں کسی لمبے تردد کی ہمیںضرورت نہیں.ہاں جب نافیہ ہو تو ضرور ہے کہ اس سے پہلے کوئی مضمون بیان ہوا ہو.خواہ اس سورۃ میں خواہ اس سے پہلے کی سورۃ میں جس کے تسلسل میں اگلی سورۃ کا مضمون بیان کیا گیا ہو.اَلشَّفَقُ شَفَقٌ مصدر بھی ہے اور شَفَقٌ کے معنی ہیں اَلْحُمْرَۃُ فِی الْاُفُقِ مِنَ الْغُرُوْبِ اِلَی الْعِشَاءِ الْاٰخِرَۃِ اَوْ اِلٰی قَرِیْبِھَا اَوْ اِلٰی قَرِیْبِ الْعَتَمَۃِیعنی شفق اس سرخی کو کہتے ہیں جو افق میں ہوتی ہے.غروب شمس کے وقت سے لے کر عشا کے وقت تک یعنی وہ عشا جسے ہم اپنی زبان میں عشا کہتے ہیں (عربی زبان میں شام کوبھی عشا کہا جاتا ہے.اسی وجہ سے وہ عشاء کو عشاء الاخریٰ کہتے ہیں) اَوْاِلٰی قَرِیْبِ الْعتَمَۃِ یا عشاء کے قریب تک فَاِذَا ذَھَبَ قِیْلَ غَابَ الشَّفَقُ جب وہ سرخی جاتی رہے تو کہتے ہیں شفق غائب ہو گئی.اصمعی کہتے ہیں سَمِعْتُ بَعْضَ الْعَرَبِ یَقُوْلُ عَلَیْہِ ثَوْبٌ کَاَنَّہٗ الشَّفَقُ وَکَانَ اَحْمَرُ یعنی میں نے بعض عربوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ اس پر میں نے ایسا کپڑا دیکھا جو شفق کی مانند تھااور وہ کپڑا جس کی نسبت انہوں نے یہ فقرہ کہا سرخ رنگ کا تھا.پس معلوم ہوا کہ شفق سُرخی پر دلالت کرتا ہے اور صحاح میں علامہ جوہری لکھتے ہیں کہ اَلشَّفَقُ بَقِیَّۃُ ضَوْئِ الشَّمْسِ وَحُمْرَتُھَا فِیْ اَوَّلِ الَّیْلِ اِلٰی قَرِیْبٍ مِنَ الْعَتَمَۃِ شفق سورج کی بقیہ روشنی اور اس کے ساتھ اس کی سُرخی کو کہتے ہیں.جو ابتداء شام سے اندھیرا ہونے کے قریب تک چلی جاتی ہے.(اقرب) بعض تفاسیر میں لکھا ہے رُوِیَ عَنْ عَلِیٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعُبَادَۃَ ابْنِ الصَّامِتِ وَاَبِیْ ھُرَیْرَۃَ وَ شَدَّادِ ابْنِ اَوْسٍ وَابْنِ عُمَرَ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ وَمَکْحُوْلٍ وَبَکْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰہِ الْمَزَانیّ وَبُکَیْرِ بْنِ الْاَشِحّ وَمَالِکٍ وَابْنِ اَبِیْ ذِئْبٍ وَعَبْدِ الْعَزِیْز بْنِ اَبِی سَلْمَۃَ الْمَاجِشُوْن اَنَّھُمْ قَالُوْا الشَّفَقُ اَلْـحُمْرَۃُ.یعنے شفق اَلْـحُمْرَۃُ کا نام ہے.اور مجاہد کہتے ہیں.کہ قَبْلَ طَلَوْعِ الشَّمْسِ شفق سورج چڑھنے سے پہلے وقت کا نام ہے.وَاَھْلُ اللُّغَۃِ بَعْدَ غَرُوْبِھَا اور اہل لغت کہتے ہیں کہ یہ بعد غروب الشمس کا نام ہے.اسی طرح مسلم میں یہ حدیث آتی ہے.عَنْ عَبْدِ اللّٰہِ بْنِ عَمْرٍو وَعَنْ رَّسُوْلِ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ اِنَّہُ قَالَ وَقْتُ الْمَغْرِ بِ مَالَمْ یَغِبِ الشَّفَقَ کہ مغرب کا وقت اس وقت تک ہے.جب تک شفق غائب نہ ہو جائے یہ حدیث لکھ کر صاحب ابنِ کثیر لکھتے ہیں فَفِیْہِ دَلِیْلٌ اَنَّ مَاقَالَ اَصْحَابُ اللُّغَۃِ صَحِیْحٌ وَالشَّفَقُ حُمْرَۃٌ بَعْدَغُرُوْبِ الشَّمْسِ.اس میں سے یہ دلیل نکلتی ہے کہ اصحاب لغت کا یہ خیال کہ غروب شمس کے بعد افق میں جو سُرخی رہ جاتی ہے.اس کا نام شفق ہے
Page 503
بالکل صحیح ہے.(تفسیر ابن کثیر زیر آیت ۱۶.۲۵ سورۃ الانشقاق) مجاہد کی دلیل یہ ہے کہ چونکہ آیت میںرات کا لفظ بعد میں ہے.اس لئے شفق سے مراد دن ہے وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَآ اُقْسِمُ بِالشَّفَقِ وَالَّیْلِ وَمَا وَسَقَ چونکہ یہاں مقابلہ ہے رات سے.اِس لئے شفق کا اشارہ دن کی طرف ہونا چاہیے.مگر یہ دلیل محض عقلی ہے.اور مجاہد نے واضح کر دیا ہے.کہ وہ کسی لغت پر اس کی بنیاد نہیں رکھ رہے بلکہ ایک عقلی دلیل پیش کر ر ہے ہیں حالانکہ عقلًا رات کے معنی کرتے ہوئے بھی شفق کا لفظ درست ہے.اس لئے کہ شفق کا وقت وہ ہوتا ہے.جب دن کی روشنی کچھ باقی ہوتی ہے.پس تقابل پھر بھی موجود ہے.چنانچہ اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ میں شہادت کے طور پر پیش کرتا ہوں اس وقت کو جب کہ دن جاتا رہے گا.مگر اس کی روشنی کچھ کچھ باقی رہے گی.اور میں شہادت کے طور پرپیش کرتا ہوں رات کو جب اس کی تاریکی پھیل جائے گی.پس یہاں تقابل موجود ہے.اس لئے خلاف لغت شفق کے معنی دن کرنے کی کوئی وجہ نہیں.وَسَقَہٗ وَسَقَہٗ یَسِقَہٗ وَسَقاً کے معنی ہوتے ہیں جَمَعَہٗ وَحَمَلَہٗ کسی چیز کو جمع کیا.اور اس کو اٹھا لیا وَسَقَ الْبَعِیْرَ کے معنی ہوتے ہیں حَمَّلَہٗ الْوَسْقِ اس پر وسق لا د دیا (اقرب) وسق کے معنی کسی جانور کی طاقت کے مطابق بوجھ کے ہیں.چنانچہ وَسْقُ الْبَعِیْرِ کے معنی ہوتے ہیں حِمْلُ البَعِیْرِ یعنی ایک اونٹ کا بوجھ (اقرب) بعض نے وسق کے وزن بھی بتائے ہیں.چنانچہ عام طور پر ساٹھ صاع کا ایک وسق سمجھا جاتا ہے.لیکن اہل حجاز ۳۲۰ رطل کا اور اہل عراق ۴۸۰ رطل کا ایک وسق قرار دیتے ہیں.وَسَقَ الْبَعِیْرَ وَسِیْقًا کے معنی ہوتے ہیں سَاقَۃُ اونٹ کو چلایا.مفسرین لکھتے ہیں کہ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَمُجَاہِدٍ وَالْحَسَنُ وَقَتَادَۃُ وَمَا وَسَقَ وَمَا جَمَعَ یعنی ابن عباس مجاہد حسن اور قتادہ کہتے ہیں کہ وَمَا وَسَقَ کے معنی وَمَا جَمَعَ کے ہیں یعنی جو اس نے جمع کیا.قتادہ اس کی تفسیر کرتے ہیں وَمَا جَمَعَ مِنْ نَجْمٍ وَدَابَّۃٍ جو کچھ بوٹیاں اور جانور وغیرہ یا ستارے ہیں ان کو جمع کیا وَقَالَ عِکْرِمَۃُ واللَّیْلِ وَمَا وَسَقَ یَقُوْلُ مَاسَاقَ مِنْ ظُلْمَۃٍ.عکرمہ اس کے معنی چلانے کے لیتے ہیں.یعنی جو ظلمت تھی اس کو وہ دھکیل کر لے آئی.سائق وہ ہوتا ہے جو پیچھے سے دھکّا دیتا ہے.اور قائد وہ ہوتا ہے جو آگے سے کھینچتا ہے پس وَمَاوَسَقَ کے یہ معنی ہوں گے.کہ جس اندھیرے کو وہ دھکا دے کر آگے لے آئے.اِتَّسَقَ اِتَّسَقَلغوی طور پر وَسَقَ کا باب افتعال ہے.اور اِتَّسَقَ الْاَمْرُ کے معنی ہوتے ہیں اِنْتَظَمَ وَاسْتَویٰ کام ٹھیک ہو گیا منظم ہو گیا اور درست ہو گیا.(اقرب) مفردات میں لکھا ہے.اَلْاِتِّسَاقُ اَ لْاِجْتِمَاعُ
Page 504
وَالْاِطِّرَادُ کہ اتسقاق کے معنی ہیں.اجتماع اور اطراد اور اطراد کے معنی ہیں کوئی چیز دوسری چیز کے پیچھے آئی.اور ٹھیک ہو گئی.چنانچہ کہتے ہیں اِطَّرَدَ الْاَمْرُاَیْ تَبِعَ بَعْضُہٗ بَعْضاً وَاسْتَقَامَ.اِطراد کے معنی ہوتے ہیں کِسی چیز کے سارے حصے جمع ہو کر وہ کام ٹھیک ہو گیا.(المنجد) فرّاء اِتَّسَقَ کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں.کہ اِتَّسَاقُہُ اِمْتَلَاءُہَ واجْتَـمَاَعُہٗ وَاسْتِوَائُ ہٗ لَیْلَۃَ ثَلَاثَ عَشْرَۃَ وَرَابِعَ عَشْرَۃَ اِلٰی سِتِّ عَشْرَۃَ وَھُوَ اِفْتَعَلَ مِنَ الْوَسَقِ الَّذِیْ ھُوَ الْجَمْعُ (تفسیر القرطبی سورۃ انشقاق زیر آیت ۱۶ تا ۲۱ )یعنی اتساق کے معنی چاند کے پورا روشن ہو جانے اور مکمل ہو جانے کے ہیں.جو تیرھویں رات سے سولہویں رات تک ہوتا ہے.وُہ یہ بھی کہتے ہیں.کہ یہ وَسَقَ کے لفظ سے باب افتعال ہے جس کے معنے جمع کرنے کے ہوتے ہیں.حسن بصری کہتے ہیں کہ اِتَّسَقَ کے معنی ہیں اِمْتَلَأَ وَاجْتَمَعَ بھر گیا.اور اکٹھا ہو گیا.قتادہ کہتے ہیں کہ اس کے معنی ہیں اِسْتِدَارَ گول ہو گیا وَیُقَالُ اَمْرُ فُلَانٍ مُتَّسِقٌ اَیْ مُجْتَمِعٌ (فتح البیان زیر آیت ھذا)عرب کہتے ہیں کہ فلاں شخص کا معاملہ متسق ہے.یعنی بالکل ٹھیک ہے.(فتح البیان) ابن کثیر میں ہے قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ اِذَااجْتَمَعَ وَاسْتَویٰ ابن عباس کہتے ہیں کہ اِتَّسَقَ کے معنے ہیں جمع ہو گیا اور درست ہو گیا.(تفسیر ابن کثیر زیر آیت ھٰذا) وَکَذَا قَالَ عِکْرَمَۃُوَمُجَاھِدٌ وَسَعِیْدُ بْنُ جُبَیْرٍ وَمَسْرُوْقٌ وَاَبُوْصَالِحٍ وَالضَّحَاکُ وَابْنُ زَیْدٍ اِذَا اتَّسَقَ اِذَااسْتَوَیٰ یعنی عکرمہ.مجاہد.سعید بن جُبیر.مسروق.ابو صالح.ضحاک اور ابن زید نے بھی اِذَااتَّسَقَ کے یہ معنی کئے ہیں.کہ اِذَااسْتَویٰ یعنی جب پورا پورا ہو گیا.اور ٹھیک ہو گیا وَ قَالَ الْحَسَنُ اِذَااجْتَمَعَ اِذَا امْتَلَأَ حسن بصری سے یہ بھی معنی مروی ہیں کہ وَالْقَمَرِ اِذَااتَّسَقَ کے معنے ہیں بھر گیا.اور روشنی مکمل ہو گئی وَقَالَ قَتَادَۃُ اِذَا اسْتَدَارَ.قتادہ کہتے ہیں اس کے معنی یہ ہیں کہ جب اس کی گولائی پوری ہو گئی.وَمعْنٰی کَلَامِہِ اَنَّہٗ اِذَاتَکَامَلَ نُوْرُہٗ وَاَبْدَرَ.(ابن کثیر زیر آیت ھذا) ابن کثیر کہتے ہیں کہ قتادہ کا مطلب یہ ہے کہ اتساق کے معنی یہ ہیں.کہ جب چاند کا نور پورا ہو گیا.اور وہ بدر بن گیا.فَلَاۤ اُقْسِمُ بِالشَّفَقِکے معنے پرانے مفسرین کے نزدیک اور اس کی تردید علامہ آلوسی اپنی تفسیر فتح البیان میں لکھتے ہیں کہ اِتَّسَقَ: اِجْتَمَعَ نُوْرُہٗ وَصَارَ بَدْرًا یعنی اِتَّسَقَ کے معنے یہ ہیں.کہ اس کا نور مکمل ہو گیا.اور وہ بدر بن گیا.(روح المعانی زیر آیت ھٰذا) صاحب کشّاف اِتَّسَقَ کے معنوںمیں لکھتے ہیں کہ اِجْتَمَعَ وَاسْتَوَیٰ لَیْلَۃَ اَرْبَعَۃَ عَشَرَ یعنی اِس کے معنی یہ ہیں کہ چاند نے اپنے نور کو مکمل کر لیا اور وہ چودھویں رات کا ہو گیا.وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ اِتَّسَقَ اِسْتَویٰ وَعَنْہٗ قَالَ لَیْلَۃَ ثَلَاثَ عَشَرَ (تفسیر کشاف زیر آیت ھذا)ابن عباس بھی اِتَّسَقَ کے معنی اِسْتَویٰ کے کرتے ہیں.اور
Page 505
کہتے ہیں کہ اِس سے مراد یہ ہے کہ چاند تیرھویں رات کا ہو گیا.تفسیر.ان معنوں کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم مندرجہ بالا تین آیتوں کو دیکھتے ہیں.تو ان میں تین حالتیں بیان کی گئی ہیں.اول حالت یہ بتائی گئی ہے کہ ہم تمہارے سامنے شفق کی حالت کو پیش کرتے ہیں.شفق جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے یقینی اور قطعی طور پر سورج کے ڈوب جانے کے بعد اتنے عرصہ کا نام ہے.جب روشنی اور سُرخی ابھی باقی ہوتی ہے.اور وَسَقَ کے معنی جمع کرنے کے بتائے جا چکے ہیں.پس وَالَّیْلِ وَمَا وَسَقَ کے یہ معنی ہوئے کہ رات جب وہ اپنی ساری کیفیتوں کو جمع کر لیتی ہے.آخر رات لکڑیاں جمع نہیںکیا کرتی.کہ یہ خیال کیا جائے کہ نہ معلوم رات کیا کچھ جمع کر لے گی.ہر چیز اپنے اندر بعض خاص صفات رکھتی ہے.اور جب ساری صفات اس میں جمع ہو جائیں تو وہ مکمل ہو جاتی ہیں پس وَالَّیْلِ وَمَاوَسَقَ کے یہ معنی ہوئے کہ رات جب اکٹھا کر لیتی ہے یعنی ان ساری صفات کو جو رات کو کامل رات بنانے والی ہیں اپنے اندر جمع کر لیتی ہے وَالْقَمَرِ اِذَااتَّسَقَ اور ہم چاند کو شہادت کے طور پر پیش کرتے ہیں جب وہ تیرھویں یا چودھویں رات کا ہو جائے گا.جس طرح رات نے اپنی ساری چیزوں کو جمع کر لیا تھا.یعنی اندھیرا اور خاموشی اور دوسری چیزیں جو رات سے وابستہ ہیں.اسی طرح چاند اپنی ساری طاقتوں کو جمع کرلے گا اور چاند اپنی ساری طاقتوں کو چودھویں رات میں ہی جمع کیا کرتا ہے.مفسرین نے اس جگہ یہ معنی کئے ہیں کہ یہاں اس کی تدریج بیان کی گئی ہے.اور بتایا گیا ہے کہ دنیا میں اِس طرح تدریجی طور پر ترقیات ہوا کرتی ہیں.اوربعضوں نے یہ معنی کئے ہیں کہ ان آیات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کے زمانہ کی ترقی کا ذکر ہے.لیکن یہ آیات بالبداہت اِس خیال کو ردّ کرتی ہیں.اس لئے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم تو ظلمتِ شب میں نازل ہوئے تھے وہاں شفق کا سوال ہی کو نسا تھا.پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کو تو خدا تعالیٰ نے سورج قرار دیا ہے.اور یہاں قمر کا ذ کر ہے.اور قمر وہ ہوتا ہے جو دوسرے سے نور لیتا ہے.رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کب قمر تھے کہ اس کے بعد بدر بن گئے.آپ تو سور ج تھے.پس یہ معنی قلّت تدبر کا نتیجہ ہیں.بات یہ ہے کہ پہلی سورتوں میں بتایا گیا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جب کُفر دنیا پر چھا جائے گا.جیسے سورۂ تکویر اور تطفیف وغیرہ میں ذکر تھا اور اِ س سورۃ میں جیسا کہ مَیں نے بیان کیا ہے اسلام کی ترقی کا ذکر ہے کفر کا نہیں.گو کفر کا ذکر ساتھ ہے مگر ان سورتوں میں کفر کا ذکر اصل تھا اور اسلام کا ذکر تابع تھا اور اس سورۃ میں اسلام کا ذکر اصل مقصد ہے اور کفر کا ذکر اس کے تابع ہے.جیسے اَذِنَتْ لِرَبِّھَا وَحُقَّتْ سے استدلال کر کے بتایا جا چکا ہے پس جب اسلام کی دوبارہ ترقی کا ذکر کیا گیا.تو لازماًیہ سوال پیدا ہوتا تھا.کہ اسلام کا تنزل کب ہو گا.اِس لئے اللہ تعالیٰ ان سارے تغیرات کا ذکر کرتا ہے.جو
Page 506
رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کی بعثت کے بعد مسلمانوں پر آنے والے تھے.رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کو سراج منیر کہا جا چکا ہے.اور سراج منیر جب غروب ہو گا.تو لازماً ایک شفق کی حالت پیدا ہو گی.اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے.فَلَآ اُقْسِمُ بِالشَّفَقِ یعنی مَیں شہادت کے طور پرپیش کرتا ہوں تمہارے سامنے اس زمانہ کو جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کا نور لوگوں کی نظروں سے غائب ہو جائے گا.شفق کا لفظ اس لئے استعمال فرمایا کہ شفق کے وقت بھی سورج موجود ہوتا ہے اور رات کے وقت بھی سورج موجود ہوتا ہے قمر کے وقت بھی سورج موجود ہوتا ہے.لیکن وہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے.جب اوپر کی سورتوں میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کے تنزل کی طرف اشارہ فرمایا.تو کسی انسان کا ذہن اس طرف بھی جا سکتا تھا.کہ شائد اس وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کی نبوت ناکارہ ہو جائے گی فرماتا ہے ناکارہ نہیں ہو گی بلکہ وہ شفق اور لیل کا زمانہ ہو گا.اور شفق اور لیل کے وقت سورج مٹ نہیں جاتا وہ موجود ہوتا ہے.مگر لوگ اِس سے فائدہ نہیں اٹھاتے.ان الفاظ کے ذریعہ اس طرف اشارہ کیا گیا ہے.کہ تنزلِ اسلام تنزلِ محمدیت کی وجہ سے نہیں ہو گا بلکہ تنزل مسلمین کی وجہ سے ہو گا.کسی قوم کا تنزل دو سببوں میں سے کسی ایک سبب سے ہوا کرتا ہے.یا تو لیڈ ر بگڑ جاتا ہے.اور اس کی وجہ سے قوم بگڑ جاتی ہے.اور یا لیڈر تو صحیح حالت پر قائم رہتا ہے.مگر قوم اس سے مونہہ پھیر لیتی ہے.یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ اسلام میں جو تنزل کی خبریں دی گئی ہیں.وہ تنزل اور انحطاط محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کے بگڑنے کی وجہ سے نہیں ہو گا.بلکہ مسلمانوں کے بگڑنے کی وجہ سے ہو گا.اور وہ آپ سے دُور جا پڑیں گے.اور اس طرح نور ہدایت حاصل کرنے سے محروم رہیں گے.جیسے شفق اور لیل سورج کے مٹ جانے کی وجہ سے نہیں آتیں.بلکہ زمین کے سورج سے اوجھل ہو جانے کی وجہ سے آتی ہیں.اِس میں ایک لطیف اشارہ اس امر کی طرف بھی ہے.کہ زمین چکر کھاتی ہے.کیونکہ اگر سورج کو چکر والا سمجھا جاتا تو یہ مثال غلط ہو جاتی.تب یہ معنی بنتے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم نعوذ باللہ بھاگ گئے.حالانکہ خدا یہ بتا تا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم نہیں بھاگے.بلکہ تم بھاگے.پس یہ مثال اسی صورت میں صحیح طور پر چسپاں ہو سکتی ہے جب ہم یہ سمجھیں کہ زمین چکّر کھاتی ہے.شفق سے مراد یہ شفق کا زمانہ اس وقت سے شروع ہوا جس کی طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم نے اس حدیث میں اشارہ فرمایا تھا خَیْرُکُمْ قَرْنِیْ ثُمَّ الَّذِیْنَ یَلُوْنَھُمْ ثُمَّ الَّذِیْنَ یَلُوْنَھُمْ ثُمَّ یَکُوْنُ بَعْدَھُمْ قَوْمٌ یَخُوْنُوْنَ وَلَا یُؤْتَمنُوْنَ وَیَشْھَدُوْنَ وَلَا یُسْتَشْھَدُوْنَ وَیَنْذُرُوْنَ وَلَا یَفُوْنَ وَیَظْھَرُ فِیْھِمُ السِّمَنُ (بخاری
Page 507
کتاب فضائل اصحاب النبی باب فضائل اصحاب النبی ) یعنی میرے بعد تین صدیوں تک کا زمانہ تواچھا ہے لیکن پھر خرابیاں پھیل جائیں گی.گویا آپ نے ابتدائی تین صدیوں کو خیر وبرکت والا قرار دیا ہے.پس یہ تین صدیاں تھیں.رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کے زمانہ کے سورج کی.اِس کے بعدسورج غائب ہوا.اور شفق کا زمانہ شروع ہوا.یعنی وہ زمانہ جب نور اور ظلمت ابھی ملے ہوئے تھے.پھر وہ زمانہ آیا.جب رات نے اپنی ساری تاریکیوں کو جمع کر لیا.اس جگہ ایک اورلطیفہ بھی یاد رکھنے والا ہے.اور وہ یہ کہ جبکہ شفق کا وقت بہت کم ہوتا ہے.اور وہ عام طور پر رات کا حصہ سمجھا جاتا ہے.پھر اللہ تعالیٰ نے شفق کو الگ کیوں بیان کیا.اسکی وجہ یہ ہے.کہ اسلام میں شفق کے زمانہ کو ایک خصوصیت حاصل ہونے والی تھی.اور وُہ یہ کہ عام طور پر شفق کا وقت چھوٹا ہوتا ہے.اور رات کا لمبا.لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کی امت سے خدا تعالیٰ کا یہ معاملہ مقدرتھا.کہ ان کے لئے شفق کا زمانہ لمبا ہو اور رات کا چھوٹا اور اس طرح شفق کا وقت اپنی ذات میں ایک مستقل حیثیت اختیار کر لے.چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کے زمانہ کے بعد ایسا ہی ہوا مسلمانوں میں ہمیشہ ایسے لوگ کھڑے ہوتے رہے جنہوں نے شفق کا کام کیا.اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کے نور کو دنیا سے غائب ہونے نہیں دیا.درحقیقت بارہویں اور تیرہویں صدی ہی اصل میں تاریک راتیں تھیں.اگرچہ غور کرنے سے ان میں بھی کچھ نہ کچھ شفق کا زمانہ نظر آ جاتا ہے.وَالَّیْلِ وَمَا وَسَقَ اور رات جب وہ وساق اختیار کر لے.اس سے صاف پتہ لگتا ہے کہ شفق وسق تک چلی جائے گی.اِس میں جہاں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نہیں مٹے گا بلکہ مسلمان اس نور سے مونہہ پھیر لیں گے.وہاں اس طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے.کہ جب وہ رات آئے گی تو اتنی تاریک اور بھیانک ہو گی.کہ وہ تمام چیزیں جو رات کو مکمل بناتی ہیں.ان کو وہ اپنے اندر جمع کر لے گی.جب رات کامل طور پر دنیا میں چھا جاتی ہَے.تو اس میں چوریاں بھی ہوتی ہیں.ڈاکے بھی پڑتے ہیں.قتل بھی ہوتے ہیں سانپ بھی نکلتے ہیں.بِچھو بھی باہر آجاتے ہیں.اور اندھیرا بھی اس طرح چھا جاتا ہے.کہ کوئی چیز نظر نہیں آتی.پس وَالَّیْلِ وَمَا وَسَقَ میں بتایا کہ وہ فتنہ بڑا شدید ہو گا.اور وُہ ساری چیزیں اس میں جمع ہو جائیں گی.جو رات کو مکمل رات بنانے والی ہوتی ہیں.شفق لیل اور قمر کو بطور شہادت پیش کرنے کا مطلب فَلَآ اُقْسِمُ بِالشَّفَقِ وَالَّیْلِ وَمَا وَسَقَ وَالْقَمَرَ اِذَااتَّسَقَ یہ تین آیات اپنے مطلب کو اس قدر واضح کر دیتی ہیں کہ مفسرین کا یہ نتیجہ نکالنا ان میں تدریج بتائی گئی ہے.بالکل
Page 508
باطل نتیجہ ثابت ہوتا ہے.پہلے شفق کا ذکر کیا گیا ہے.اس کے بعد انتہائی تاریک رات کا اور اس کے بعد قمر کا جو اپنی منازل طے کر کے بدر بن جاتا ہے.اور یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں جو کبھی اکٹھی نہیں ہوتیں نہ شفق کے بعد لازمًا انتہائی تاریک رات آتی ہے.اور نہ انتہائی تاریک کے بعد بدر نکلا کرتا ہے.آخر کوئی مفسر مجھے بتائے کہ وہ کون سا بدر ہے.جو وَالَّیْلِ وَمَا وَسَقَ کے بعد نکلتا ہے.مگر یہاں وَالَّیْلِ وَمَا وَسَقَ کا پہلے ذکر کیا گیا ہے.اور بدر کا بعد میں ذکر کیا گیا ہے پس یہاں تدریجی ترقی کا کوئی ذکر نہیں اور نہ جسمانیات کا کوئی قانون بیان ہو رہا ہے.بلکہ رُوحانی نقطۂ نگاہ سے اسلام کے تنزل اور اس کی ترقی کے مختلف ادوار کا ذکر کیا جا رہا ہے.پس لیل سے یہاں کوئی دنیوی رات مراد نہیں.بلکہ روحانی رات مراد ہے.اور دنیوی اور روحانی راتوں میں یہ فرق ہوتا ہے کہ دنیوی راتوں میں بدر سے پہلی راتیں تاریک نہیں ہوتیں.بلکہ روشن ہوتی ہیں.مثلاً ۱۴ سے پہلے ۱۲ یا ۱۳ تاریخ کی راتیں تاریک نہیں ہوں گی.انتہائی تاریک راتیں ۲۸-۲۹ ہوں گی.لیکن روحانی دنیا میں بدرِ کامل اس وقت ظاہر ہوتا ہے.جب اس سے پہلے ایک سخت تاریک رات دنیا پر چھائی ہوئی ہوتی ہے پس وَالَّیْلِ وَمَا وَسَقَ کے بعد وَالْقَمَرِ اِذَااتَّسَقَ رکھ کر بتا دیا گیا ہے کہ یہاں جسمانی نہیں بلکہ روحانی شفق روحانی رات اور روحانی بدر کا ذکر کیا جا رہا ہے.اِس لئے تدریج کا یہاں کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا.فرماتا ہے وَالْقَمَرِ اِذَااتَّسَقَ ہم شہادت کے طور پر چاند کو پیش کرتے ہیں.جب وہ بدر بن جاتا ہے.یہ مسیح موعود کی بعثت کے متعلق اتنی واضح پیشگوئی ہے کہ اس کے بعد کسی کا یہ کہنا کہ قرآن میں مسیح موعود کا ذکر نہیں خطرناک ظلم ہے.یہاں تین حالتیں بیان کی گئی ہیں.اور بتایا گیا ہے.کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کے بعد شفق کا زمانہ بہت لمبا ہو گا.اس کے بعد ایک چھوٹا سا تاریک زمانہ آئے گا.مگر باوجود اس کے کہ وہ چھوٹا ہو گا اس قدر تاریک ہو گا کہ کس قدر تاریکی دنیا میں ممکن ہے.سب اس میں جمع ہو جائے گی.اس کے بعد یکدم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم سے روشنی لینے والے وجودوں میں سے ایک بدر بن جائے گا.اور رات پر اس طرح چھا جائے گا.کہ اسے شروع سے لے کر آخر تک منور کر دے گا.بدر کا یہی کام ہوتا ہے کہ وہ رات کو شروع سے آخر تک روشن کر دیتا ہے.وہ روحانی بدرِ کامل بھی اپنے نور کو دنیا میں اس طرح پھیلا دے گا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کا بُعد لوگوں کو محسوس نہیں ہو گا.یہ نہایت ہی واضح اور مکمل نقشہ ان تغیرات کا کھینچا گیا ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے لے کر آخر تک رونما ہونے تھے.اور جنہوں نے اسلام پر اثر انداز ہونا تھا.(اقرب)
Page 509
لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍؕ۰۰۲۰ تم ضرور درجہ بدرجہ ان حالتوں پر پہنچو گے.حَلّ لُغَات.اَلطَّبَقُ اَلطَّبَقُکے معنی ہیں اَلْقَرْنُ مِنَ الزَّمَانِ ایک صدی.اَلنَّاسُ ایک زمانہ کے لوگ اَلْجَمَاعَۃُ جماعت.اَلْحَالُ.حال (اقرب) اَلطَّبَقُ.اَلْمُطَابَقَۃُ (مفردات) تفسیر.فرماتا ہے ہم اپنی ذات ہی کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ تم ضرور ایک درجہ کے بعد دوسرے درجہ پر جائو گے.لَتَرْکَبُنَّ میں لام اور نون مشدّد لانے کی ضرورت ہی کیا تھی.اگر یہ آیات اپنے اندر کوئی اہم پیشگوئی نہیں رکھتی تھیں.اس آیت کی بناوٹ ہی واضح کر رہی ہے.کہ ان آیات کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ پر چسپاں کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا.بلکہ یہ واقعات آئندہ زمانہ کے متعلق بطور پیشگوئی بیان کئے گئے ہیں.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں نہ شفق کا کوئی سوال پیدا ہو سکتا تھا.نہ انتہائی تاریک رات کا اور نہ اس وقت کوئی قمر تھا جو اتساق اختیار کر کے بدر بن گیا ہو.پس یہ آیات قطعی طور پر بعد کے زمانہ سے ہی تعلق رکھتی تھیں.لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ میں عن کے معنے بعد کے عَنْ کے عربی زبان میں بہت سے معنی ہوتے ہیں جن میں سے ایک یہ ہیں کہ عَنْ علاوہ اور معنوں کے بعد کے معنی بھی دیتا ہے جیسے کہتے ہیں عَنْ قَلِیْلٍ اَزُوْرُکَ اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ بَعْدَ قَلِیْلٍ اَزُوْرُکَ اس جگہ بھی عَنْ کے معنی بعد کے ہی ہیں اور مراد یہ ہے کہ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا بَعْدَ طَبَقٍ یعنی تم ایک درجہ کے بعد دوسرے درجہ تک پہنچو گے.جیسا کہ حل لغات میں لکھا جا چکا ہے طبق کے معنی مطابق کے بھی ہوتے ہیں.اور اس کے معنی حال کے بھی ہوتے ہیں.اسی طرح طبق کےایک معنی جماعت کے بھی ہوتے ہیں.یہاں حالت اور جماعت دونوں معنی لگ سکتے ہیں یعنی ہم اپنی ذات کی قسم کھا کر کہتے ہیں.کہ تم ضرور ان چاروں حالتوں میں سے ایک کے بعد دوسری پر گزرتے ہوئے چلے جائو گے.اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں.کہ تم ایک جماعت کے بعد دوسری جماعت پر سوار ہوتے جائو گے.یعنی جس جس جماعت کے حالات بیان ہوئے ہیں.اس جماعت کی حالت تم پر وارد ہوتی جائے گی.اب دیکھ لو کس طرح خدا تعالیٰ نے ان تمام باتوں کو پورا کیا.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کامہر منور تین صدیوں تک دنیا کو روشن کرتا رہا.اس کے بعد شفق کا زمانہ آیا.جو بہت لمبا عرصہ رہا.سید عبدالقادر صاحب جیلانی.حضرت معین الدین صاحب چشتی.حضرت محی الدین صاحب ابن عربی اور دُوسرے کئی بزرگ اِ س زمانہ
Page 510
شفق میں آئے.اور انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کے نور اور آپ کی تعلیم کو قائم رکھا.اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس وقت رات پڑ گئی تھی مگرپھر بھی کوئی شخص سورج کے وجود سے انکار نہیں کر سکتا تھا.کیونکہ شفق کی سُرخی موجود تھی.اِس کے بعد بارہویں اور تیرھویں صدی میں تاریکی آئی اور ایسی بھیانک اور خطرناک شکل میں کہ وَالَّیْلِ وَمَا وَسَقَ کا نظارہ نظر آنے لگ گیا.رات اپنے اندر جس قدر بلائیں جمع کر سکتی ہے.وہ تمام بلائیں.اور تمام آفتیں اور تمام مصیبتیں اُس تاریک رات نے اپنے اندر جمع کر لی تھیں.وہ اسلام اور مسلمانوں کے لئے ایسا تباہی کا زمانہ تھاکہ جس کی نظیر پہلے کسی زمانہ میں نہیں ملتی.پھرا س انتہائی تاریک رات کے معًا بعد وَالْقَمَرِ اِذَااتَّسَقَ کے مطابق ایک قمر بدر کی صورت اختیار کر گیا.اور وُہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کا نُور دنیا تک پہنچانے لگ گیا.حضرت مسیح موعود کا نور سہولویں صدی تک اِس پیشگوئی پر غور کرو اور دیکھو کہ یہ پیشگوئی نہ صرف معنًا پوری ہوئی بلکہ لفظًا لفظًا پوری ہوئی ہے.چنانچہ اتساق کی تشریح کرتے ہوئے بتایا جا چکا ہے کہ تیرھویں رات سے سولہویں رات تک کے چاند کے لئے اتساق کا لفظ استعمال کرتے ہیں.یہ بات بھی نمایاں طور پر پُوری ہوئی.کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام تیرھویں صدی میں پیدا ہوئے.چودھویں صد ی میں آپ نے دعویٰ فرمایا.اور پھر آپ نے بطور پیشگوئی اعلان فرمایا کہ مسیح موعود کا زمانہ تین سو سال تک ہے.یعنی سولہویں صدی کے آخر تک.چنانچہ آپ تحریر فرماتے ہیں.’’مسیح موعود کا زمانہ اس حد تک ہے.جس حد تک اس کے دیکھنے والے یا دیکھنے والوں کے دیکھنے والے اور یا پھر دیکھنے والوں کے دیکھنے والے دنیا میں پائے جائیں گے.ا ور اس کی تعلیم پر قائم ہوں گے.غرض قرونِ ثلاثہ کا ہونا برعائت منہاج نبوت ضروری ہے.‘‘ (تریاق القلوب روحانی خزائن جلد ۱۵ صفحہ ۴۷۸ بقیہ حاشیہ) اسی طرح فرمایا: ’’ابھی تیسری صدی آج کے دن سے پُوری نہیں ہو گی کہ عیسٰی کے انتظار کرنے والے کیا مسلمان اور کیا عیسائی سخت نومید اور بدظن ہو کر اس جھوٹے عقیدہ کو چھوڑ یں گے.اور دنیا میں ایک ہی مذہب ہو گا.اور ایک ہی پیشوا مَیں تو ایک تخم ریزی کرنے کے لئے آیا ہوں.سو میرے ہاتھ سے وہ تخم بویا گیا.اور اب وہ بڑھے گا.اور پھولے گا.اور کوئی نہیں جو اس کو روک سکے‘‘.( تذکرۃ الشہادتین روحانی خزائن جلد ۲۰ صفحہ ۶۷)
Page 511
پھر آپ مخالفین کے انجام کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں.’’ مقدریوں ہے کہ وہ لوگ جو اِس جماعت سے باہر ہیں وہ دن بدن کم ہوتے جائیں گے.اور تمام فرقے مسلمانوں کے جو اِس سلسلہ سے باہر ہیں.وہ دن بدن کم ہو کر اس سلسلہ میں داخل ہوتےجائیںگے یا نابود ہوتے جائیں گے جیسا کہ یہودی گھٹتے گھٹتے یہاں تک کم ہو گئے.کہ بہت ہی تھوڑے رہ گئے.ایسا ہی اِس جماعت کے مخالفوں کا انجام ہو گا اور اِس جماعت کے لوگ اپنی تعداد اور قوتِ مذہب کے رو سے سب پر غالب ہو جائیں گے.‘‘ (براہین احمدیہ حصہ پنجم روحانی خزائن جلد ۲۱ صفحہ ۹۵) غرض مسیح موعود کا زمانہ تیرہویں صدی سے شروع ہو کر سولہویں صدی کے آخر تک پہونچے گا.اور یہی لغت والے کہتے ہیںکہ اتساق کے معنی یہ ہیں کہ وہ چاند جو تیرھویں سے سولہویں تک جاتا ہے.اگر یہاں صرف بدر کا لفظ رکھ دیا جاتا.تو مضمون میں وہ وسعت پیدا نہ ہوتی.جو وَالْقَمَرِ اِذَااتَّسَقَ کے الفاظ سے پیدا ہوئی.کیونکہ اتساق کا لفظ رکھ کر مسیح موعود کے زمانہ کی طرف بھی اشارہ کر دیا گیا ہے.کہ تیرھویں صدی میں وہ پیدا ہو گا.چودھویں صدی میں اس کا ظہور ہو گا.اور سولہویںصدی کے آخر تک اس کا اثر ترقی کرتا جائے گا.فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ۰۰۲۱ پھر ان (لوگوں )کو کیا ہوا ہے.کہ ایمان نہیں لاتے.تفسیر.فَمَا لَھُمْ لَایُؤْمِنُوْنَ.یعنی اس زمانہ کے لوگوں کو کیا ہو گیا.یہ کہہ سکتے تھے کہ اتساق کے زمانہ کا ہم کو پتہ نہیں.کہ وہ کب ہو گا.یہ کہہ سکتے تھے کہ ہم نے تو بدر کامل کا ظہور نہیں دیکھا.مگر یہ لوگ شفق اور لیل کو تو دیکھ چکے تھے.اور اس پر قیاس کر کے سمجھ سکتے تھے.کہ جب شفق بھی آچکی اور لیل بھی ظاہر ہو گئی.تو وَالْقَمَرِ اِذَااتَّسَقَ کی پیشگوئی کے پُورا ہونے کا وقت بھی آ جائے گا.مگر وہ تولیل کو دیکھ کر بالکل مایوس ہو کر بیٹھ گئے.اور یہ خیال کرنے لگ گئے کہ اب اسلام کبھی ترقی نہیں کر سکتا.پس تعجب ہے کہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا.انہوں نے شفق کو بھی دیکھا.انہوں نے لیل کو بھی دیکھا.مگر یہ نہ سمجھا.کہ بدر کامل کا ظہور بھی مقدر ہے.لَایُؤْمِنُوْنَ ایمان نہیں لاتے.یعنی اِس بات پر ایمان نہیں لاتے کہ بدر اِس تاریک وتاررات پر چھا جائے
Page 512
گا.اور تمام ظلمات کو پھاڑ دے گا.وَ اِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْاٰنُ لَا يَسْجُدُوْنَؕؑ۰۰۲۲ اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جائے.تو سجدہ نہیں کرتے.حَلّ لُغَات.یَسْجُدُوْنَ یَسْجُدُونَ یَسْجُدُ سے جمع کا صیغہ ہے.اور سَجَدَ یَسْجُدُ کے معنی ہوتے ہیں خَضَعَ وَاَغْنٰی عاجزی کی اورعجز کا اظہار جھکنے سے کیا نیز کہتے ہیں سَجَدَتِ السَّفِیْنَۃُ لِلرِّیَاحِ اور معنی ہوتے ہیں طَاعَتْھَا وَمَالَتْ بِمَیْلِھَا.کہ کشتی نے ہوا کی اطاعت کی.اور جدھر ہوا کا رخ تھا.ادھرچل پڑی (اقرب) پس یَسْجُدُوْنَ کے معنی ہوں گے.وہ فرمانبرداری کرتے ہیں.اور لَایَسْجُدُوْنَ کے معنی ہوںگے فرمانبرداری نہیں کرتے.تفسیر.لَا یَسْجُدُوْنَ کے دو معنے یہاں سجدہ کے دو معنی ہیں اوّل یہ کہ وہ فرمانبرداری نہیں کرتے.دوسرے یہ کہ جب قرآن کا دوبارہ نزول ہو رہا ہے.تو وہ کیوں اس شکریہ میں سجدہ نہیں کرتے.اس میں یہ پیشگوئی مخفی تھی.کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا.جب قرآن دنیا سے مٹ جائے گا.اور ایمان ثریا پر چلا جائے گا.اس وقت ایک بدری وجود پھر قرآن کریم کو دنیا میں واپس لائے گا.پھر اس قرآن کو پڑھا جائے گا پھر اس قرآن پر عمل شروع ہوگا.پھر اس کے احکام کو تازہ کیا جائے گا.فرماتا ہے.یہ ہماری اتنی بڑی نعمت ہے.کہ چاہیے تھا خدا تعالیٰ کے اس عظیم الشان فضل پر وہ سجدوں میں گر جاتے.کہ انہیں ان کی کتاب واپس مل گئی.ان کا روحانی خزانہ جو مدتوں سے ضائع ہو چکا تھا.پھر ان کے گھروں میں واپس آ گیا.مگر یہ لوگ ایسے ناشکر گزار ہیں کہ الٹا اس پر الزام لگاتے ہیں کہ وہ قرآن میں تحریف کر رہا ہے.یا یہ معنی ہیں کہ وہ بدری وجود توقرآن پیش کرے گا مگر یہ لوگ بجائے قرآن کی فرمانبرداری کرنے کے اس کے سامنے حدیثوں یا ائمہ سلف کے اقوال کو پیش کریں گے.قرآن کی طرف نہیں جائیں گے.ہماری جماعت کے ایک دوست میاں نظام الدین صاحب کاایک مشہور واقعہ ہے.جو میں نے بارہا سنایا ہے.کہ وہ ابھی بیعت میں شامل نہیں تھے.کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اگر میں قرآن کریم کی سو آیتیں ایسی نکلوا کر لے آئوں.جن سے حیات مسیح ثابت ہوتی ہو.تو کیا آپ مان جائیں گے کہ
Page 513
حضرت عیسٰی زندہ ہیں.حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا سو آیتوں کا کیاسوال ہے.آپ ایک آیت ہی پیش کر دیں.تومیں ماننے کے لئے تیار ہوں.انہوں نے کہا کہ میں دس آیتیں تو ضرور لا کر آپ کو دکھائوں گا.اور یہ کہہ کر خوش خوش مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی کے پاس گئے.تاکہ قرآن سے ایسی آیتیں نکلوا لائیں.مولوی محمد حسین صاحب ان دنوں لاہور میں تھے.حضرت خلیفہ اول رضی اللہ عنہ بھی جموں سے چھٹی پر وہاں تشریف لائے ہوئے تھے.اور وفات و حیات مسیح پر بحث کے لئے آپس میں شرائط کا تصفیہ ہو رہا تھا.حضرت خلیفہ اول ؓ فرماتے تھے.کہ اس مسئلہ کا قرآن سے فیصلہ ہونا چاہیے.اور مولوی محمد حسین صاحب یہ کہتے تھے کہ حدیثیں بھی شامل ہونی چاہئیں.آخر بڑی بحث اور ردّو کد کے بعد حضرت خلیفۂ اولؓ نے مان لیاکہ بخاری بھی شامل کر لی جائے.مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی کو فخر کرنے کی بہت عادت تھی.حضرت خلیفۂ اولؓ نے جب ان کی اتنی بات مان لی.کہ بخاری سے بھی تائیدی رنگ میں ثبوت پیش کیا جا سکتا ہے.تو ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانا نہ رہا.مسجد میں بیٹھ کر انہوں نے لاف زنی شروع کر دی کہ مولوی نورالدینؓ نے یوں دلیل دی.اور مَیں نے اسے یوں پکڑا.اس نے اس طرح کہا.اور مَیں نے اسے اس طرح گرایا.اتنے میںمیاں نظام الدین صاحب بھی وہاں جا پہونچے.اور کہنے لگے مولوی صاحب ان بحثوں کو چھوڑئیے مَیں مرزا صاحب کو منوا کر آرہا ہوں.کہ اگر مَیں قرآن سے دس آیتیں ایسی نکال کر لے آئوں.جن سے حیات مسیح ثابت ہوتی ہو.تو وہ اپنے عقیدہ کو ترک کر دیں گے.آپ مہربانی فرما کر مجھے جلدی سے ایسی دس آیتیں قرآن سے لکھ دیں.تاکہ مَیں مرزا صاحب کے سامنے پیش کروں.مولوی صاحب جو فخر ومباہات سے کام لے رہے تھے.اور بار بار کہہ رہے تھے.کہ میں نے مولوی نورالدینؓ کویوں رگیدا.اسے اس طرح پکڑا.اور اس طرح گرایا.ان کے تو یہ بات سنتے ہی حواس اڑ گئے.اور جوش میں کہنے لگے تجھے کس پاگل اور جاہل نے کہا تھا.کہ تو اس معاملہ میں دخل دیتا.مَیں دو مہینے بحث کر کے مولوی نورالدینؓ کو حدیث کی طرف لایا تھا.تو پھر اس مسئلہ کو قرآن کی طرف لے گیا ہے.یہ اتنا گندہ فقرہ تھا کہ میاں نظام الدین صاحب جو اپنے دل میں اسلام کی محبت رکھتے تھے.اسے برداشت نہ کر سکے.تھوڑی دیر تک حیرت سے ان کا مونہہ دیکھتے رہے.اور پھر کہنے لگے مولوی صاحب اگر یہی بات ہے.تو پھر جدھر قرآن ہے ادھر ہی میں ہوں.چنانچہ وہ وہاںسے واپس آئے اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بیعت میں شامل ہو گئے (حیات احمد از یعقوب علی عرفانی صفحہ ۱۴۳ تا۱۴۵ )پس اس آیت کے ایک یہ بھی معنی ہیں کہ وہ بدری وجود قرآن پیش کرے گا.مگر وہ اُسے ضعیف حدیثوں اور لوگوں کے اقوال کی طرف لانے کی کوشش کریں گے.اسی طرح اس کے
Page 514
یہ بھی معنے ہیں کہ اس وقت قرآن آسمان پر جا چکا ہو گا.تب ایک بدری وجود قرآن کو پھر واپس لائے گا.مگر یہ لوگ ایسے ہیں کہ خدا تعالیٰ کا اس عظیم الشان نعمت کے واپس ملنے پر بھی کوئی شکر ادا نہیں کریں گے.کہ اس نے ان پرکتنا بڑا رحم کیا.کتنا بڑا انعام کیا.کہ ان کے مذہب کو اس نے بچا لیا.اور انہیں ہلاکت کے گڑھے میں گرتے گرتے تھام لیا.اگر یہ معنی نہ کئے جائیں تو قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْاٰنُکا وَالْقَمَرِ اِذَااتَّسَقَ کے ساتھ کوئی جوڑ ہی نہیں بنتا لیکن ہم حدیث صحیح سے اس کا جوڑ بتا سکتے ہیں.جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ آخری زمانہ میں قرآن کی تعلیم مٹ جائے گی.ایمان ثریا پر چلا جائے گا لَا یَبْقٰی مِنَ الْاِسْلَامِ اِلَّا اِسْمُہٗ وَلَا یَبْقٰی مِنَ الْقُرْاٰنِ اِلَّا رَسْمُہٗ (مشکوٰۃ المصابیح کتاب العلم) اسلام کا صرف نام اور قرآن کا صرف رسم الخط باقی رہ جائے گا.معارف اور حقائق اور علوم سب آسمان پر اٹھ جائیں گے تب ایک فارسی الاصل انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہو گا جو ایمان کو ثریا سے واپس لائے گا.اور قرآنی علوم کو زندہ کر دے گا.پس ہم اس آیت کے جو معنے کرتے ہیں وہ پورے طور پر یہاں چسپاں ہو جاتے ہیں.لیکن اور لوگ اس کے کیا معنی کر سکتے ہیں.وہ شفق اور لیلؔ اور قمرؔ کے ساتھ قرآن کا کوئی جوڑ بتا ہی نہیں سکتے.بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُكَذِّبُوْنَٞۖ۰۰۲۳ بلکہ (بات اتنی بڑھ گئی ہے کہ) جنہوں نے اس قرآن کا کفر کیا ہے.وہ تو (اسے) جھٹلاتے ہیں.تفسیر.بَلْ کے معنی زیادتی کے ہیں یعنی صرف یہی بات نہیں کہ وہ قرآن کے دوبارہ نزول پر خدا تعالیٰ کے حضور سجدۂ شکر ادا نہیں کرتے.اور اس کی فرمانبرداری نہیں کرتے.بلکہ الٹے تکذیب کرنے لگ جاتے ہیں.یعنی بجائے اطاعت شعاری سے کام لینے کے وہ اس موعود کی تکذیب کریں گے.وہ قرآن کی آیتیں پیش کرے گا.مگر یہ لوگ کہیں گے ہم ان آیتوں کو نہیں مانتے.
Page 515
وَ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يُوْعُوْنَٞۖ۰۰۲۴ اور اللہ اسے جسے وہ (اپنے دلوں میں) چھپائے ہوئے ہیں.خوب جانتا ہے.حَلّ لُغَات.یُوْعُوْنَ یُوْعُوْنَ اَوْعٰی سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے.اور اَوْعٰی الشَّیءَ وَالْکَلَامَ کے معنی ہوتے ہیں حَفِظَہٗ وَجَمَعَہٗ کسی کلام کو یاد کیا.اور اکٹھا کیا.اور جب اَوْعَی الزَّادَ وَالْمَتَاعَ کہیں تو معنی ہوتے ہیں جَعَلَہٗ فِی الْوِعَائِ وَجَمَعَہٗ فِیْہِ کہ سامان کو تھیلے میں رکھا اور محفوظ کیا.(اقرب) پس یُوْعُوْنَ کے معنی ہوں گے (۱)حفظ کرتے ہیں اور جمع کرتے ہیں (۲)محفوظ کرتے ہیں.تفسیر.اللہ خوب جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا کچھ بھرا ہوا ہے.قرآن ان کے دلوں سے نکل جائے گا.اور یہی باقی رہ جائے گا کہ فلاں نے یہ کہا ہے فلاں نے یہ لکھا ہے.یُوْعُوْنَ کے ایک معنی حفظ کے بھی ہیں.چنانچہ اَوْعٰی الشَّیءَ اَوِ الْکَلَامَ کے معنی ہوتے ہیں حَفِظَہٗ وَجَمَعَہٗ اس نے حفظ کیا.اور جمع کیا.پس وَاللّٰہُ اَعْلَمُ بِمَا یُوْعُوْنَ کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ انہوں نے دوسروں کے اقوال جو حفظ کر رکھے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خوب جانتا ہے.یا ان کے دلوں میں جو کچھ بھرا ہے اسے وہ خوب جانتا ہے.فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍۙ۰۰۲۵ پس (ان کے مخفی خیالات اور ظاہر اعمال کی وجہ سے)انہیںدردناک عذاب کی خبر دے دے.تفسیر.فرماتا ہے ہم نے تو ان کو فائدہ پہنچانے کے لئے یہ سب انتظام کیا تھا ہم چاہتے تھے کہ نور سے ان کو حصہ ملے.اور خدا تعالیٰ کے قرب کی راہوں پر چلنا ان کے لئے آسان ہو.مگر وہ تاریکی کے کونوں میں بیٹھے رہے.انہوں نے خدا تعالیٰ کے نور سے مونہہ پھیر لیا.اس کی برکات کو رد کر دیا.اور خدا تعالیٰ کے احسان پر سجدۂ شکر ادا کرنے کی بجائے اس کی آیات کی تکذیب کی.اس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ وہ بہت بڑے دکھ میں مبتلا کئے جائیں گے.
Page 516
اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ اَجْرٌ مگر وہ (لوگ) جو ایمان لائے.اور انہوں نے مناسب حال عمل کئے.ا نہیں ایک نہ ختم ہونے والا (نیک) غَيْرُمَمْنُوْنٍؒ۰۰۲۶ اجر ملنے والا ہے.حَلّ لُغَات.اَلْمَمْنُوْنُ اَلْمَمْنُوْنُ کے معنی ہیں اَلمَقْطُوْعُ کٹا ہوا (اقرب) پس غَیْرُ مَمْنُوْنٍ کے معنی ہوں گے غیر مقطوع.تفسیر.حضرت مسیح موعود کی ماتحتی کے بغیر کوئی روحانی ترقی نہیں کر سکتا اِس آیت کے وہی معنی ہیں جن کی طرف حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتب میں اشارہ فرمایا ہے کہ آیندہ کوئی شخص خدا تعالیٰ کے قرب اور اس کی ولایت کا مقام حاصل نہیں کر سکتا.مگر وہی جو میری جماعت میں شامل ہو گا.اور میری اقتدا اور متابعت کا دم بھرے گا.آیندہ زمانہ میں اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نبی بھی مبعوث ہو گا.تو اس کے لئے ضروری ہو گا.کہ وہ مسیح موعود کے دروازہ میں سے گزرے.بے شک شکل میں تبدیلی آ جائے گی.مگر اس کا تعلق مسیح موعود سے منقطع نہیں ہو گا.جس طرح محمدی نور کبھی منقطع نہیں ہوسکتا اسی طرح اس نور کا سلسلہ اب قیامت تک منقطع نہیں ہوسکتا.اس میں شک نہیں یہاں مومنوں کی جماعت کا ذکرکیا گیا ہے.مگر جماعت درحقیقت نبی کے تابع ہوتی ہے.اور چونکہ مسیح موعود اب قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لئے مسیح موعود اور خدا کے رسول ہیں.اس لئے اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ آیندہ جو بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقرب ہونا چاہے گا.اس کے لئے ضروری ہو گا کہ وہ مسیح موعود کے واسطہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے.اور مسیح موعود کے واسطہ سے ہی خدا تعالیٰ تک پہنچے.اس کے بغیر کوئی انسان الٰہی برکات کو حاصل نہیں کر سکتا.خ خ خ خ
Page 517
سُوْرَۃُ الْبَرُوْجِ مَکِّیَّۃٌ سورۃ بروج.یہ سورۃ مکی ہے.وَھِیَ دُوْنَ الْبَسْمَلَۃِ اِثْنَتَانِ وَ عِشْرُوْنَ اٰیَۃً اور اِس کی بسم اللہ کے سوا بائیس آیات ہیں.سورۃ بروج مکی ہے یہ سورۃ بھی پہلی چند سورتوں کے تسلسل میں ہے اور مکّی سورۃ ہے.مفسرین لکھتے ہیں کہ لَاخَلَافَ فِیْ مَکِّیَّتِھَا اس کے مکّی ہونے میں کوئی اختلاف نہیں.لیکن انگریز مصنفین نے اس میں ایک شبہ پیدا کیا ہے.نولڈکے جرمن مستشرق اِسے زمانۂ اوّل کے پہلے دَور یعنی ابتدائی اَڑھائی سال کے اندر کی قرار دیتا ہے.مگر اس کے ساتھ ہی اُس نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ مَانَقَمُوْا سے لے کر ذٰلِکَ الْفَوْزُ الْکَبِیْرُ تک بعد کی ہیں.بعد کی آیات سے یہ مراد نہیں کہ کسی اور نے ملا دی ہیں.بلکہ اس کے نزدیک مدنی زندگی میں خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملائی ہیں.وہ کہتا ہے اِن آیتوں کی عبارت مکّی عبارتوں سے مختلف ہے.کیونکہ یہ آیتیں باقی آیتوں سے لمبی ہیں اور مدنی سورتوںسے ملتی ہیں.مستشرقین کا مکی اور مدنی آیات میں تمیز کرنے کا ایک بےہودہ طریق وہیری اس پر ایک اور بات زائد کرتا ہے.وہ کہتا ہے اِس سورۃ میں مومنات کا لفظ آیا ہے.جیسا کہ آتا ہےاِنَّ الَّذِيْنَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوْبُوْا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَ لَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيْقِ اور مومنات کا لفظ مدنی سورتوں میں ہی مروّج ہوا ہے مکّی سورتوں میں نہیں.اس طرح نولڈکے کے خیالات کی وہ تصدیق کرتا ہے.نولڈکے کا خیال ہے کہ آٹھویں آیت سے لے کر گیارھویں آیت تک مدنی زمانہ کی آیات ہیں.جہاں تک مکّی اور مدنی آیتوں کا سوال ہے ہمیں اِس بحث سے کوئی تعلق نہیں کہ کوئی آیت مکّی ہے یا مدنی.ہمارے نزدیک ہر آیت خدا تعالیٰ کی نازل کی ہوئی ہے اور ہر آیت ہمارے لئے قابلِ عمل ہے خواہ وہ مکّہ میں نازل ہوئی ہو یا مدینہ میں.اس لئے ان کے مکی یا مدنی ہونے سے ہمارے نزدیک کوئی خاص فرق نہیں پڑتا.اور اگر منکرین اسلام کے نظریہ کو لو تو اُن کے نزدیک ہر آیت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بنائی ہوئی ہے.اس لئے اُنہیں بھی اِس بحث سے کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا کہ کوئی آیت مکّی ہے یا مدنی.لیکن یہ بتانے کے لئے کہ مستشرقینِ یورپ اسلام کے متعلق بعض دفعہ کیسی رکیک اور بے بنیاد باتیں بیان کرتے ہیں.مَیں اس اعتراض پر بحث کرتا ہوں.
Page 518
جہاں تک مَیں سمجھتا ہوں نولڈکے کا یہ دعویٰ خلافِ عقل ہے.کیونکہ چند آیات کے ذرا لمبا ہو جانے سے اُن کے بعد میں نازل ہونے کا کوئی ثبوت نہیں نکل سکتا.آخر قرآن کریم کے متعلق ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ سارے کا سارا اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے.اور نولڈکے اور اُس کے ساتھیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ سارا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہے.بہرحال کسی تیسرے شخص کا تو یہاں سوال ہی نہیں.اب اگر یہ بات مان لی جائے کہ قرآن سارے کا سارا خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے تو یہ کہنا کہ مدینہ میں خدا تعالیٰ لمبی آیتیں نازل کر سکتا تھا لیکن مکّہ میں نہیں حماقت ہے اور اگر اس نظریہ کو لے لیا جائے کہ تمام سورتیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بنائی ہوئی ہیں تب بھی نولڈکے اور دوسرے مستشرقین کا یہ کہنا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکّہ میں لمبی آیتیں نہیں بنا سکتے تھے لیکن مدینہ میں بنا سکتے تھے بےہودہ بات ہے.کسی حکمت کے ماتحت اگر عام طور پر مکّی آیتیں چھوٹی ہیں تو اِس کے یہ معنے نہیں کہ اِن آیات کو بنانے والا لمبی آیتیں ضرورت کے موقع پر نہیں بنا سکتا تھا.پس عقلی طور پر یہ دعویٰ بالکل باطل ہے.واقعات کے لحاظ سے بھی یہ بات درست ثابت نہیں ہوتی اس لئے کہ مومنات کا لفظ جس پر وہیری نے بنیاد رکھی ہے اور کہا ہے کہ یہ صرف مدنی سورتوں میں آیا ہے مکّی سورتوں میں بھی آتا ہے.چنانچہ سورۂ نوح کی آیت ہے رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَ لِوَالِدَيَّ وَ لِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَّ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتِ١ؕ وَ لَا تَزِدِ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا تَبَارًا(نوح:۲۹) یہاں مومنات کا لفظ بھی آیا ہے اور یہ آیت بھی لمبی ہے.گویا دونوں باتیں اِس آیت میں پائی جاتی ہیں.اور سورۂ نوح وہ سورۃ ہے جس کے مکی ہونے میں کوئی اختلاف نہیں.فتح البیان کا مصنّف لکھتا ہے.اِنَّھَا مَکِّیَّۃٌ قَالَ الزُّبَیْرُ نَزَلَتْ بِمَکَّۃَ یعنی سورۂ نوح مکّی ہے اور حضررت زبیرؓ کہتے ہیں کہ یہ مکّہ میں نازل ہوئی تھی.روح المعانی کے مصنف لکھتے ہیں مَکِّیَّۃٌ بِالْاِتِّفَاقِ اِس پر سب اتفاق کرتے ہیں کہ سورۂ نوح مکّی ہے.نولڈکے جو سورۂ بروج کی بعض آیتوں کے لمبا ہونے سے یہ استدلال کرتا ہے کہ وہ مدنی ہیں وہ بھی سورۂ نوح کے متعلق لکھتا ہے کہ یہ پہلے پانچ سال کی سورتوں میں سے ہے.اور وہیری جو مومنا ت کے لفظ کی وجہ سے سورۂ بروج کی آیات کو مدنی قرار دیتا ہے وہ بھی سورۂ نوح کے متعلق لکھتا ہے کہ یہ ساتویں سال نبوّت کی ہے.پس نولڈکے اور وہیری کی اپنی شہادتوں سے یہ بات ثابت ہے کہ مکّی سورتوں میں مومنات کا لفظ بھی آتا ہے اور اس کی بعض آیات لمبی بھی ہیں.پس معلوم ہوا کہ سورۂ بروج کے متعلق جو انہوں نے استدلال کیا تھا وہ محض ایک ڈھکونسلہ تھا اور ڈھکونسلہ چونکہ یاد نہیں رہتا اِس لئے کِسی موقع پر کچھ نتیجہ نکال لیااور کسی موقع پر کچھ.بات یہ ہے کہ قرآن کریم کے متعلق مستشرقینِ یورپ جس چیز کو دلیل قرار دیتے ہیں وہ محض ظنّ اور تخمین ہوتی
Page 519
ہے.اور ہمارے ہندوستانی نَو تعلیم یافتہ جب کوئی بات اُن کے مُنہ سے سُنتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ وہ وحی الٰہی سے بھی زیادہ مقدّس ہے.حالانکہ اگر غور سے کام لیا جائے تو ایک ڈھکونسلے سے زیادہ اُس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی.بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۰۰۱ (مَیں) اللہ (تعالیٰ) کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا (اور) بار بار رحم کرنے والا ہے (شروع کرتا ہوں).وَ السَّمَآءِ ذَاتِ الْبُرُوْجِۙ۰۰۲وَ الْيَوْمِ الْمَوْعُوْدِۙ۰۰۳ (مجھے) قسم ہے بُرجوں والے آسمان کی.اور اُس دن کی بھی جس کا وعدہ ہے.حَلّ لُغَات.بُرُوْجٌ.بُرُوْجٌ بُرْجٌ کی جمع ہے.اور بُرْجٌ کے معنے عربی زبان میں اَلرُّکْنُ وَالْحِصْنُ وَالْقَصْرُ کے ہیں.یعنی عمارت کے مضبوط حصّہ یا قلعہ یا محل کو بُرج کہتے ہیں.نیز ستاروں کی گردش کی جگہ کو بھی بُرج کہتے ہیں (اقرب) اسی طرح کہتے ہیں بَرِجَتْ عَیْنُہٗ بَرَجًا کَانَ بَیَاضُھَا مُحْدَقًا بِاالسَّوَادِ کُلِّہٖ لَا یَغِیْبُ مِنْ سَوَادِ ھَا شَیْءٌ فَھِیَ بَرْجَائُ وَجَمْعُھَا بُرْجٌ.یعنی جب آنکھ کے متعلق بَرِجَتْ کا لفظ استعمال کریں تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ آنکھ کی سیاہی کا اس کی سفیدی نے چاروں طر ف سے خوب گھیرا کیا ہوا ہے اور وہ عورت جس کی آنکھ اِس قسم کی ہو اس کو بَرْجَائُ کہتے ہیں.اور بہت سی عورتوں کو بُرْجٌ کہتے ہیں.اِسی سے یہ محاورہ ہے کہ رَأَیْتُ بُرْجًا فِیْ بُرْجٍ یعنی مَیں نے ایک قلعہ میں بہت سی خوبصورت عورتیں دیکھیں جن کی آنکھوں کی سفیدی نے اُن کی آنکھوں کی سیاہی کا احاطہ کیا ہوا تھا.(اقرب ) گویا بُرْجٌ مفرد بھی ہے اور اِس کے معنے رُکْن ؔ.حِصن ؔ.اور قصر ؔ کے ہیں اور برْجٌ جمع بھی ہے جس کا مفرد بَرْجَائُ ہے.اور اِس کے معنے یہ ہوتے ہیں کہ وہ عورت جس کی آنکھوں کی سفیدی سیاہی کے چاروں طرف ہو.اس کا یہ مطلب نہیں کہ بعض عورتوں کی آنکھوں کی سیاہی ساری آنکھ میں پھیلی ہوئی ہوتی ہے.بلکہ مطلب یہ ہے کہ اُس کی آنکھیں بڑی ہیں پُتلی خوب کھلتی ہے اور سفیدی نظر آجاتی ہے.تفسیر.بروج سے مراد بارہ ستاروں کے بارہ مقامات فرماتا ہے ہم شہادت کے طور پر آسمان کو پیش کرتے ہیں جو بروج والا ہے.یہ بروج کیا ہے؟ مفسرین نے اِس سے مراد علمِ ہیئت کے بروج لئے ہیں.وہ کہتے ہیں بارہ ستاروں کے لئے بارہ بُرج ہوتے ہیں جن کے نام یہ ہیں (۱)اَلْحَمْلُ (۲)اَلثَّوْرُ (۳)اَلْجَوْزَاءُ (۴)اَلسَّرْطَانُ (۵)اَلْاَسَدُ (۶)السُّنْبَلَۃُ (۷)اَلْمِیْزَانُ (۸)اَلْعَقْرَبُ (۹)اَلْقَوْسُ
Page 520
(۱۰)اَلْجدِّیُّ (۱۱) اَلدَّلْوُ (۱۲)اَلْحُوْتُ بعض کہتے ہیں کہ سات سیّارے اِن بارہ بُرجوں میں چکّر کھاتے ہیں.اور گو بروج بارہ ہی ہیں مگر خصوصیت کے لحاظ سے وہ سات سیّاروں سے مخصوص ہیں.چنانچہ (۱)مریخ کے لئے حمل اور عقرب (۲)زہرہؔ کے لئے ثور اور میزان (۳)عطاردؔ کے لئے ہیں جوزاء اور سُنبلہ (۴)قمرکے لئے سرطان (۵)شمسؔ کے لئے اسد (۵)مشتریؔ کے لئے قوس اور حُوت (۷)زحلؔ کے لئے جدّی اور دَلْومخصوص ہیں.ابن مردویہ جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بروج کیا چیز ہیں تو آپؐ نے فرمایا اَلْکَوَاکِبُ (روح المعانی زیر آیت ھذا)یعنی اُن سے مرادکواکب ہیں.غرض بُرج کا لفظ لُغت کے لحاظ سے ایسے مقام کے لئے بولا جاتا ہے جہاں بادشاہ یا اُمراء ٹھہرتے ہوں.اور علم ہیئت والوں کی اصطلاح میں جو رائج ہو چکی ہے بُرج یا تو ستاروں کو اور یا پھر سیّاروں کی گردش کے دائرہ کو کہتے ہیں جہاں وہ گردش کرتے ہیں.بہرحال پرانی ہیئت اِس بات پر متفق ہے کہ بُرج بارہ ہیں.اِس بناء پر آیت کے یہ معنے ہوں گے کہ ہم شہادت کے طور پر آسمان کو پیش کرتے ہیں جس میں بارہ بُرج ہیں.یعنی بارہ ایسے مقام ہیں جہاں ستارے ٹھہرتے ہیں.وَالْیَوْمِ الْمَوْعُوْدِ اور پھر ہم شہادت کے طور پر یومِ موعود کو پیش کرتے ہیں.اگر بُرج کے معنے بارہ مقامات کے لئے جائیں تو یہ یومِ موعود تیرھواں مقام ہوا.گویا بارہ مقاموں کو بھی اور یوم موعود کو بھی اللہ تعالیٰ شہادت کے طور پر پیش کرتا ہے.اور بارہ اور یومِ موعود مل کر تیرہ ہو گئے.جب ہم اس کو وَالْقَمَرِ اِذَا اتَّسَقَ والی آیت سے ملاتے ہیں تو پہلی سورت سے اس کی ترتیب بالکل واضح ہو جاتی ہے وہاں فرمایا تھا ہم شہادت کے طور پر چاند کو پیش کرتے ہیں جب وہ تیرہویں رات میں داخل ہوتا ہے.اور یہاں فرمایا گیا ہے ہم بارہ بروج اور یومِ موعود کو شہادت کے طور پر پیش کرتے ہیں.پس یہاں بھی تیرہ زمانوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا.اور اس طرح اس کا ایک گہرا تعلق پچھلی سورۃ سے ثابت ہو گیا.سورئہ بروج کا پہلی سورۃ سے تعلق یہاں درحقیقت اُس مضمون کو بیان کیا گیا ہے جو پچھلی سورۃ میں بیان کیا گیا تھا.مگر شکل اور ہے.اور جو کچھ پچھلی سورۃ میں بیان کیا گیا تھا اُس کی صداقت کی ایک دلیل بھی اِس سورۃ میں بیان کی گئی ہے.پچھلی سورۃ میں فرمایا تھا فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ اِن لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ایمان نہیں لاتے.جو چیز اپنی ابتدائی حالت میں ہوتی ہے اُس پر ایمان لانا لوگوں کے لئے بہت مشکل ہوتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے اِس سورۃ کو شروع ہی اِس رنگ میں کیا ہے کہ ہم شہادت کے طور پر پیش کرتے ہیں اُن بارہ مقامات کو جہاں ستارے آکر
Page 521
ٹھہرتے ہیں.یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بارہ صدیوں میں مختلف مجددین ظاہر ہوئے اور وہ الٰہی منشاء کے مطابق تجدید دین کا کام کرتے رہے.اللہ تعالیٰ اُن مجددین کی بعثت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے.اگر ہم اُمُت محمدیہ کے تھوڑے سے اختلاف اور اسلام اور مسلمانوں کی تھوڑی سی مصیبت کو دُور کرنے کے لئے مجددین مبعوث کرتے رہے ہیںتو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اسلام پر ایک بھاری مصیبت آجائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اُس کو دُور کرنے کا کوئی سامان نہ ہو.وَ السَّمَآءِ ذَاتِ الْبُرُوْجِمیں آخری زمانہ میں بارہ مجددین کے بعد ایک مامور کے مبعوث کئے جانے کی پیشگوئی پس وَ السَّمَآءِ ذَاتِ الْبُرُوْجِ کو فَمَالَھُمْ لَایُؤْمِنُوْنَ کے جواب میں مخالفین کے سامنے ایک دلیل کے طور پر پیش کیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم آسمان کو اور اُس کے بارہ مقامات کو تمہارے سامنے پیش کرتے ہیں.جن میں ستاروں نے قیام کیایعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کی ہدایت کے لئے مختلف مجدد مبعوث ہوتے رہے.مجددین کے اِس متواتر اور پَے در پَے ظہو ر کے بعد تیرہویں مقام پر آکر تمہیں کیوں مایوسی پیدا ہو گئی اور کیوں تم نے یہ خیال کر لیا کہ اللہ تعالیٰ اب لوگوں کی ہدایت کے لئے اپنے کسی مامور کو مبعوث نہیں کرے گا.تمہارے پاس شہادت موجود ہے کہ پہلی صدی آئی اور اُس میں خدا تعالیٰ نے ایسے آدمی کھڑے کئے جو تجدید دین کا کام کرتے رہے.دوسری صدی آئی اور اُس میں خدا تعالیٰ نے ایسے آدمی کھڑے کئے.تیسری صدی آئی تو پھر یہی واقعہ ہوا.چوتھی صدی آئی تو پھر بھی ایسا ہی ہوا اور یہ سلسلہ چلتا چلا گیا یہاں تک کہ بارہ صدیوں میں بارہ دفعہ تمہارے لئے خدا تعالیٰ نے یہ ثبوت مہیّا کیا کہ وہ اپنے دین کی مدد اور اُس کی نصرت کے لئے ہمیشہ ایسے آدمی کھڑے کیا کرتا ہے جو اُس کی طرف سےمظفّر و منصور ہوتے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دنیا میں پھیلاتے ہیں.مگر عجیب بات یہ ہے کہ بارہ جو غیر موعود تھے اُن کو توتم نے مان لیا مگر تیرہواں جو موعود تھا اُس کی بعثت کو تسلیم کرنے سے تم نے انکار کر دیا.حالانکہ باقی وہ ہیں جن کے متعلق محض مبہم الفاظ میں خبر دی گئی تھی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن کے متعلق صرف اتنا فرمایا تھا کہ اِنَّ اللّٰہَ یَبْعَثُ لِھٰذِہِ الْاُمَّۃِ عَلٰی رَأْسِ کُلِّ مِائَۃِ سَنَۃٍ مَنْ یُّجَدِّدُ لَھَادِیْنَھَا (سنن ابی دائود کتاب الملاحم باب ما یذکر فی قرن المائۃ) مگر تیرہویں کا نام لے کر بتایا گیا تھا کہ وہ ایسا ایسا ہو گا اِس اِس طرح کے کام کرے گا اِن اِن علامات کے ساتھ آئے گا.یہ یہ نشانات اُس کی صداقت میں ظاہر ہوں گے.پس وہ غیر موعود جو ایک مبہم خبر کے نتیجہ میں ظاہر ہوئے تھے تم نے اُن کو تو مان لیا مگر وہ جس کا نام لے کر خدا نے خبر دی تھی.جس کی بعثت کے اُس نے نشانات بتائے تھے.جس کی تعیین کے کئی شواہد
Page 522
بتائے گئے تھے.جس کا وقت اور جس کا زمانہ تک پیشگوئیوں میں معیّن کر دیا گیا تھا تم نے اُس کا انکار کر دیا.بلکہ مسلمانوں کی یہ حالت ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت کے بعد انہوں نے یہاں تک کہنا شروع کر دیا ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کی ترقی کے لئے کِسی مصلح کی ضرورت ہی نہیں.فرماتا ہے تم کو آج بارہ صدیوں کے بعد یہ بات سُوجھی ہے.بارہ صدیوں تک تم مانتے چلے آئے کہ احیائِ اسلام کے لئے مجدّدین کی ضرورت ہوتی ہے.اسلام کی ترقی کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی انسان کے مبعوث ہونے کی احتیاج ہوتی ہے.مگر جب تیرہویں صدی آئی اور اُس میں ہم نے اپنا موعود مامور بھیج دیا تو تم نے اس کا انکار کر دیا.بلکہ یہاں تک کہہ دیا کہ ہمیں کسی مصلح کی ضرورت ہی نہیں.فَمَالَھُمْ لَا یُؤْمِنُوْنَ اُن کو کیا ہو گیا کہ جو ہمارا موعود مامور تھا جس کی تفصیلات ہم نے پہلے سےبتادی تھیںجس پر ایمان لانے کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر تاکید فرمائی تھی.جس کے درجہ اور شان کی تفخیم بڑی کثرت سے بیان کی گئی تھی اُس پر ایمان لانے سے اِن لوگوں نے انکار کر دیا اور کہہ دیا کہ یہ بات ہی غلط ہے کہ اسلام اپنی ترقی کے لئے آسمانی وجودوں کی بعثت کا محتاج ہے.فرماتا ہے ہم اسلام کی ترقی کے لئے بارہ بروج کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ غور کرو اور دیکھو کہ کس طرح ایک ایک قدم پر اللہ تعالیٰ نے اسلام کی مدد فرمائی اور کفر کے حملوں کو نابود کرنے کے لئے اپنے مقدس لوگ کھڑے کرتا رہا.پھر جب تیرہویں صدی آئی تو ہم نے اُس زمانہ میں بھی اپنا وہ موعود بھیج دیا جس کی ہم خبر دیتے چلے آئے تھے.خدا تعالیٰ کی قدرت ہے ہم پر قرآن کریم کی آیات کے یہ مطالب تو بعد میں کُھلے لیکن عجیب بات یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کا نام ہی ہماری جماعت میں مسیح موعودؑ پڑ گیاہے.جس کے معنے یہی ہیں کہ یومِ موعودِ میں ظاہر ہونے والامسیح ؑ.جس احمدیؐ سے بھی سنو.خواہ وہ عالم ہو یا جاہل.پڑھا لکھا ہو یا اَن پڑھ.اُسے یہی کہتے پائو گے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے یوں کہا.یا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی صداقت کی یہ دلیل ہے.گویا اللہ تعالیٰ نے آپؑ کا نام ہی مسیح موعود رکھ دیا.اور یہ لفظ اتنی کثرت سے استعمال ہوتا ہے.کہ مہدی کا لفظ بھی غائب ہو گیا ہے.حالانکہ مہدی کا لفظ حدیثوں میں کثرت سے استعمال ہوا ہے.مگر چونکہ قرآن کریم میں اس کو موعود قرار دیا گیا تھا اس لئے خدا نے اپنے تصرّف سے مسیح موعودؑ کے الفاظ دنیا میں رائج فرما دئیے.یوم موعود سے مراد حدیثوں میں آتا ہے عَنِ ابْنِ اَبِیْ حَاتِمٍ وَابْنِ جَرِیْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ اَلْیَوْمُ الْمَوْعُوْدُ یَوْمُ الْقِیَامَۃِ وَشَاہِدٌ یَوْمُ الْجُمُعَۃِ وَمَشْہُوْدٌ یَوْمُ الْعَرَفَۃِ
Page 523
وَشَاھِدٌ مُحَمَّدٌ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ وَمَشْھُوْدٌ یَوْمُ الْقِیَامَۃِ.(ابن کثیر زیر آیت شاھد و مشھود) یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یومِ موعود یومِ قیامت ہے.شاہد یومِ جمعہ ہے.مشہود یومِ عرفہ ہے.اِسی طرح شاہد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مشہود قیامت کا دن ہے.اِس حدیث کی صحت سے ہم کو انکار نہیں.درحقیقت یومِ موعود بہت سے ہیں.قرآن کریم سے پتہ لگتا ہے کہ جنگ بدر کا دن بھی یومِ موعود تھا کیونکہ اس جنگ کی قرآن کریم میں پیشگوئی موجود ہے.اِسی طرح جنگِ احزاب بھی موعود تھی کیونکہ اس کی پیشگوئی کی گئی تھی.فتح مکہ کا دن بھی یومِ موعود تھا کیونکہ اِ س فتح کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیشگوئی کی گئی تھی(القمر:۴۶، الفتح :۲، الاحزاب:۱۲).پس ہمیں اس سے انکار نہیں کہ اور بھی کئی یوم موعود ہیں.مگر سوال یہ ہے کہ یہاں جس یومِ موعود کا ذکر ہے وہ ایسا موعود ہے جس نے اس واقعہ کے بعد آنا ہے جس کا ذکر’’ ذات البروج‘‘ میں ہے اور ’’ذات البروج‘‘ کے بعد آنے والا یوم موعود نہ قیامت کا دن ہو سکتا ہے اور نہ کوئی اور ہو سکتا ہے.بلکہ اِ س جگہ وہی موعود مراد ہو سکتا ہے جس نے بارہ بروج کے بعد تیرہویں صدی میں ظاہر ہونا تھا.کِسی لفظ میں اشتراک کے یہ معنے نہیں ہوا کرتے کہ اس لفظ کے ہر جگہ ایک ہی معنے لئے جائیں بلکہ وہ لفظ اپنے موقع اور محل کے مطابق الگ الگ معنے دے گا.پس بے شک بدر یومِ موعود ہے.احزاب یومِ موعود ہے.فتح مکّہ یوم موعود ہے.اور ہمیں اِس سے ہر گز انکار نہیں.مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ وَ السَّمَآءِ ذَاتِ الْبُرُوْجِ کے بعد جس موعود کا ذکر ہے وہ سوائے مسیح موعود ؑکے اور کوئی نہیں.اور وَالْقَمَرِ اِذَا اتَّسَقَ میں بھی اسی موعود کی خبر دی گئی تھی.اگر اِس جگہ یومِ موعود سے مراد مسیح موعود نہیں تو سوال یہ ہے کہ وہ کون سی طاقت تھی جس نے اگلی اور پچھلی آیات میں ایسا جوڑ پیدا کر دیا کہ اُن سے جو بات بھی ثابت ہوتی ہے مسیح موعود پر چسپاں ہو جاتی ہے.قرآن کریم کا ایک طر ف وَالْقَمَرِ اِذَا اتَّسَقَ کہنا پھر وَ السَّمَآءِ ذَاتِ الْبُرُوْجِ کہہ کر شہادت میں بُروج کو پیش کرنا اور پھر علمِ ہیئت کی طرف سے اِس تحقیق کا ہونا کہ بُروج بارہ ہیں یہ سب کچھ بتا رہا ہے کہ جو کچھ ہوا الٰہی تصرف کے ماتحت ہوا.اِسی طرح اگلی آیت میں شاہد اور مشہود کا ذکر آتا ہے اور یہ ایک حقیقت ہے کہ شاہد ہزاروں ہوئے ہیں بلکہ ہر نبی شاہد ہوتا ہے.کیا دنیا میں کوئی بھی نبی ایسا ہوا ہے جس نے دلائل اور معجزات اور بیّنات سے اللہ تعالیٰ کے وجود کی گواہی پیش نہ کی ہو.یقیناً ہر نبی ایسا کرتا رہا.پس ہر نبی شاہد ہے.اِن معنوں میں کہ وہ خدا تعالیٰ کی ہستی اور اُس کی قدرت اور اُس کے جلال کا ایک زندہ گواہ ہوتا ہے.اور ہر نبی مشہود ہوتا ہے کیونکہ جب وہ دنیا میں آتا ہے خدا تعالیٰ اُس کی صداقت کے ثبوت مہیّا کرتا ہے.پس وہ خدا تعالیٰ کے لئے شاہد ہوتا ہے.اور چونکہ خدا اُس کی صداقت کے لئے نشانات و معجزات ظاہر کرتا ہے اس لئے وہ مشہود بھی ہوتا ہے.اِسی طرح ہر نبی کے زمانہ میں خدا شاہد ہوتا ہے
Page 524
کیونکہ وہ نبی کی صداقت پر گواہ ہوتا ہے اور خدا مشہود بھی ہوتا ہے کیونکہ نبی کے ذریعہ اُس کا وجود دُنیا میں پہچانا جاتا ہے.یہی وہ حقیقت ہے جس کی طرف حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اس الہام میں اشارہ کیا گیا کہ یَاقَـمْرُ یَاشَـمْسُ اَنْتَ مِنِّیْ وَاَنَا مِنْکَ (تذکرۃ صفحہ ۵۰۰ ،الحکم ۱۰؍ جنوری ۱۹۰۶ صفحہ۱)اے قمر اور اے شمس تُو مجھ سے ہے اور مَیں تجھ سے ہوں یعنی تُو قمر ہے ان معنوں میں کہ تُو نے جوکچھ نُور لیا مجھ سے لیا اور تُو شمس ہے اِن معنوںمیں کہ تیرے وجود سے میرا وجود روشن ہوا.اِسی طرح مَیں شمس ہوں کیونکہ اگر مَیں تیری مدد نہ کرتا تو دُنیا میں تُو اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکتا.اور مَیں قمر بھی ہوں کیونکہ مجھے تُو نے دنیا میں روشناس کرایا.پس جس طرح خدا شمس بھی ہوتا ہے اور قمر بھی اسی طرح نبی ایک حیثیت سے شمس ہوتا ہے اور دوسری حیثیت سے قمر ہوتا ہے.یہی حال شاہد اور مشہود کا ہے.ہر نبی شاہد ہوتا ہے اور خدا مشہود ہوتا ہے مگر دوسری طرف اِس سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ خدا شاہد ہوتا ہے اور نبی مشہود ہوتا ہے مگر اس کے یہ معنے نہیں کہ شاہد اور مشہود ہم کسی اور چیز کو نہیں قرار دے سکتے.خود اس حدیث میں جس کا مَیں نے ابھی ذکر کیا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم جمعہ کو شاہد اور یوم عرفہ کو مشہود قرار دیا ہے.دوسری طرف آپؐ نے قیامت کے دن کو مشہودقرار دےدیا ہے.پس تمام حدیثیں اپنی اپنی جگہ پر درست ہیں.ہم یوم القیامۃ کے یومِ موعود ہونے سے انکار نہیں کرتے.اسی طرح شاہد اور مشہود کے متعلق حدیثوں میں جو کچھ آتا ہے اُسے بھی تسلیم کرتے ہیں مگر دیکھنے والی بات یہ ہے کہ یہاں کون سی بات چسپاں ہوتی ہے.یہاں یومِ موعود سے مراد زمانہ مسیح موعودؑ ہے یا قیامت کا دن ہے.صاف بات ہے کہ وَالْقَمَرِ اِذَا اتَّسَقَ میں یہ بتایا گیا تھا کہ ایک سخت تاریک و تار رات کے بعد جو روحانی طور پر تمام دُنیا پر چھا جائے گی اللہ تعالیٰ ظہورِ قمر کو اتّساق کا مقام بخشے گا.اور لغتًا یہ ثابت کیا جا چکا ہے کہ قمر کے لئے اتّساق کا لفظ اُس وقت استعمال کرتے ہیں جب وہ تیرہویں رات کا ہو.گویا تیرہویں رات کے چاند کو شہادت کے طور پر پیش کیا گیا تھا.اس کے بعد سورئہ بروج میں پھر یہی ذکر فرمایا مگر اس رنگ میں کہ پہلے بارہ بروج کا ذکر فرمایا اور پھر تیرہویں نمبر پر یوم موعود کا.اِس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ اِس جگہ یومِ موعود سے مراد وہی مسیح موعودؑ ہے جس کے لئے یہ مقدر کیا جا چکا تھا کہ وہ بارہ بروج کے بعد دُنیا میں مبعوث ہو گا.یوم کے معنے وقت کے ہوتے ہیں.اگر یہ معنے مراد لئے جائیں تو یوم موعود سے مراد وقت موعود ہو گا اسی طرح یومِ نہار یعنی معروف دن کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے.اِ س صورت میں والیوم الموعود کے یہ معنے ہوں گے کہ گو مثال ہم رات کی دیتے چلے آئے ہیں مگر اپنی ذات میں وہ وقت دن کی طرح روشن ہو گا اس لئے ہم اُسے
Page 525
یومِ موعود کہہ رہے ہیں کیونکہ اُس دن خدا تعالیٰ کا نور اور جلال ظاہر ہو گا.وَ شَاهِدٍ وَّ مَشْهُوْدٍؕ۰۰۴ اور (آسمانی) گواہ کی.نیز جس پر گواہی دی گئی ہے اُس (آسمانی وجود) کی بھی.تفسیر.شاہد کی تشریح قرآن مجید میں میرے نزدیک قرآن کریم نے ایک دوسری جگہ شاہد کی جو تعریف فرما دی ہے وہی اِ س جگہ چسپاں ہوتی ہے.اللہ تعالیٰ سورۂ ہود میں فرماتا ہے اَفَمَنْ كَانَ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّهٖ وَ يَتْلُوْهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَ مِنْ قَبْلِهٖ كِتٰبُ مُوْسٰۤى اِمَامًا وَّ رَحْمَةً١ؕ اُولٰٓىِٕكَ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ١ؕ وَ مَنْ يَّكْفُرْ بِهٖ مِنَ الْاَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهٗ١ۚ فَلَا تَكُ فِيْ مِرْيَةٍ مِّنْهُ١ۗ اِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ وَ لٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُوْنَ(ہود:۱۸) یعنی کیا جو شخص اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر قائم ہے اور اُس کی صداقت کا ایک گواہ خدا تعالیٰ کی طرف سے آکر اس کی پیروی کرے گا اور اُس سے پہلے موسٰی کی کتاب تھی جو لوگوں کے لئے امام و رحمت تھی ایک جُھوٹے مدعی جیسا ہو سکتا ہے؟ اور مو سیٰ کے سچے پیرو اس پر بھی ضرور ایمان لاتے ہیں.اور ان مخالف گروہوں میں سے جو کوئی اس کا انکار کرے گا تو دوزخ کی آگ اُس کے لئے وعدہ کی جگہ ہے.پس اے مخاطب تو اس کے متعلق کسی قسم کے شک میں نہ پڑ وہ یقیناً بالکل حق ہےاور تیرے رب کی طرف سے ہے.لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لایا کرتے.شاہد سے مراد مسیح موعودؑ اِس آیت میں شَاھِدٌ مِّنْہُ کے ذریعہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بعثت کی خبر دی گئی ہے.پس شاہد مسیح موعود ہیں اور مشہود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم.یہی بات اللہ تعالیٰ نے اِس جگہ بیان فرمائی ہے کہ ہم شہادت کے طور پر اُس شاہد کو پیش کرتے ہیں جس کا دوسری جگہ ہم ذکر کر چکے ہیں.اسی طرح ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو پیش کرتے ہیں.پس شاہد سے مراد یہ ہے کہ اُس زمانہ میں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت لوگوں کے قلوب سے مٹ چکی ہو گی وہ اِس بات کی گواہی دے گا کہ آپؐ سچے ہیں اور قرآن کریم کی صداقت لوگوں پر واضح کرے گا.
Page 526
قُتِلَ اَصْحٰبُ الْاُخْدُوْدِۙ۰۰۵النَّارِ ذَاتِ الْوَقُوْدِۙ۰۰۶ خندقوں والے ہلاک ہو گئے.یعنی (خندقوں میں) آگ (بھڑکانے والے) جس میں (خوب) ایندھن (جھونکا اِذْ هُمْعَلَيْهَا قُعُوْدٌۙ۰۰۷وَّ هُمْ عَلٰى مَا يَفْعَلُوْنَ گیا) تھا.جب وہ اس (آگ) پر (دھرنا مار کر) بیٹھے ہوئے تھے.اور وہ مومنوں سے جو کچھ (معاملہ) بِالْمُؤْمِنِيْنَشُهُوْدٌؕ۰۰۸ کر رہے تھے آنکھیں کھولے کر رہے تھے.حَلّ لُغَات.اَلْاُخْدُوْدُ اَلْاُخْدُوْدُ کے معنے ہیں.اَلْحُفْرَۃُ الْمُسْتَطِیْلَۃُ فِی الْاَرْضِ.زمین میں لمبا کھدا ہوا گڑھا (اقرب) اِس کی جمع اَخَادِیْد آتی ہے.تفسیر.فرماتا ہے ہلا ک ہو گئے یا ہلاک کئے جائیں گے اَصْحٰبُ الْاُخْدُوْدِ یعنی خندقوں والے.النَّارِ.وہ خندقیں جو نار پر مشتمل ہوں گی ایسی نار پر جو ذَاتِ الْوَقُوْدِ ہو گی.ایندھن والی ہو گی.یعنی ہماری مراد اِس اُخدود سے وہ آگ ہے جو اُخدود میں جلائی جائے گی.گویا ہلاکت کا اصل سبب خندق کھودنا نہیں بلکہ خندق میں آگ جلا کر لوگوں کو مبتلائے تعذیب کرنا ہوگا.اِذْھُمْ عَلَیْھَا قُعُوْدٌ جبکہ وہ اُس پر بیٹھیں گے.وَ هُمْ عَلٰى مَا يَفْعَلُوْنَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ شُهُوْدٌ اور وہ جو کچھ مومنوں کے ساتھ کر رہے ہوں گے اُس پر وہ حاضر اور نگران ہوں گے.اصحاب الاخدود کے متعلق سابق مفسرین کے خیالات اور ان کی تردید اِن آیات کے متعلق مفسرین نے دو باتیں بیان کی ہیں.اوّلؔ یہ کہ ایبے سینیاء کا ایک بادشاہ تھاجس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اُس نے بعض لوگوں کو جو توحید پر قائم تھے عذاب دیا اور بعض نے لکھا ہے کہ یہ دانیال اور اُس کے دو ساتھیوں کے متعلق ہے جن کو بخت نصر نے عذاب دیا تھا.(روح المعانی زیر آیت ھذا) مَیں حیران ہوں کہ مفسّرین نے یہ کس طرح لکھ دیا.اصل میں یہ بائیبل کا بیان کر دہ واقعہ ہے اور وہی قرین قیاس معلوم ہوتا ہے.خصوصاً اس لئے کہ دانیال کی کتاب میں اس کا ذکر موجود ہے.دانیال باب ۳ میں یہ واقعہ اس طرح مذکور ہے.’’ اور نبوکدنضر بادشاہ نے ایک سونے کی مُورت بنوائی جس کی لمبائی ساٹھ ہاتھ اور چوڑائی چھ
Page 527
ہاتھ کی تھی.اور اُسے دُورا کے میدان صوبہ بابل میں نـصب کیا.تب نبوکد نضر بادشاہ نے لوگوں کو بھیجا کہ امیروں اور حاکموں اور سرلشکروں اور منصفوں اور خزانچیوں اور مشیروں اور مجتہدوں اور سارے صوبوں کے منصب داروں کو جمع کریں تاکہ وَے اُس مورت کی جسے نبوکدنضر بادشاہ نے نصب کیا تھا تقدیس کرنے کو آویں.تب امیر اور حاکم اور سرلشکر اور منصف اور خزانچی اور مشیر اور مجتہد اور صوبوں کے سارے منصب دار اُس مورت کی تقدیس کے لئے جسے نبوکدنضر نے نصب کیا تھا جمع ہوئے اور وَے اُس مُورت کے آگے جسے نبوکدنظر نے نصب کیا تھا کھڑے ہوئے.تب ایک منّاد نے بلند آواز سے پکارا کہ اے قومو! اے گروہو! اور اے مختلف لغتیں بولنے والو! تمہارے لئے یہ حکم ہے کہ جس وقت قرنائے اور نَے اور ستار اور رباب اور بربط اور چغانہ اور ہر طرح کے باجے کی آواز سنو تو اِس سونے کی مُورت کے آگے جسے نبوکدنضربادشاہ نے نصب کیا ہے اوندھے مُنہ گرو اور سجدہ کرو.اور جو کوئی اوندھے منہ نہ گرے اور سجدہ نہ کرے تو اسی گھڑی جلتی بھٹی کے بیچ میں ڈالا جائے گا.سو اُسی دم جس وقت ساری قوموں نے قرنائے اور نَے اور ستار اور رباب اور بربط اور ہر طرح کے باجے کی آواز سنی اُسی وقت ساری قومیں اور گروہیںاور زبان بولنے والے اُس مورت کے آگے جسے نبوکدنضر بادشاہ نے نصب کیا تھا اوندھے منہ گرے اور انہوں نے سجدہ کیا.سو اُس وقت کئی ایک کسدی نزدیک آئے اور انہوں نے یہودیوں پر نالش کی.انہوں نے نبوکدنضربادشاہ کے آگے عرض کی.اے بادشاہ! تا ابد جِیتا رہ.اے بادشاہ تُو نے حکم کیا ہے کہ جو قرنائے اور نَے اور ستار اور رباب اور بربط اور چغانہ اور ہر طرح کے باجے کی آواز سُنے سو اُس سونے کی مُورت کے آگے زمین تک جھکے اور سجدہ کرے.اور جو کوئی زمین تک نہ جُھکے اور سجدہ نہ کرے سو ایک جلتی بھٹی کے بیچ میں ڈالا جائے گا.اب چند یہودی جنہیں تُو نے بابل کے صوبے کی کارپردازی پر متعین کیا ہے.یعنی سدرک اور میسک اور عبید نجُو.اِن آدمیوں نے تیری تعظیم نہیں کی ہے.وَے تیرے معبودوں کی عبادت نہیں کرتے ہیں اور اُس سونے کی مُورت کو جسے تُو نے نصب کیا سجدہ نہیں کرتے.تب نبوکدنضر نے قہر اور غضب سے حُکم کیا کہ سدرک اور میسک اور عبید نجُو کو حاضر کریں.سو اُنہوں نے اُن آدمیوں کو بادشاہ کے حضور حاضر کیا.نبوکدنضر نے ارشاد کیا اور اُنہیں کہا کہ اے سدرک اور میسک اور عبیدنجُو! کیا یہ سچ ہے کہ تم لوگ میرے معبودوں کی عبادت نہیں کرتے ہو اور اُس سونے کی مُورت کو جسے مَیں نے نصب کیا سجدہ
Page 528
نہیں کرتے.تس پر بھی اگر مستعد رہو کہ جس دم کرنائے اور نَے اور ستار اور رباب اور بربط اور چغانہ اور ہر طرح کے باجے کی آوازسُنو تو اُسی دم اُس مورت کے آگے جسے مَیں نے کھڑا کیا اوندھے مُنہ گر پڑو اور سجدہ کرو تو بہتر.پر اگر سجدہ نہ کرو گے تو اُسی گھڑی ایک آگ کی جلتی بھٹی کے بیچ ڈالے جائو گے اور وہ خدا کون ہے جو تمہیں میرے ہاتھ سے چھڑا وے گا.سدرک اور میسک اور عبیدنجُو نے جواب میں بادشاہ سے کہا کہ اے نبوکد نضر اِس مقدمے میں تجھے جواب دینا ہم ضرور نہیں جانتے.دیکھو تو.ہمارا خدا ہے جس کی عبادت ہم کرتے ہیںوہ ہمیں آگ کی جلتی بھٹی سے چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے اور وہ اے بادشاہ تیرے ہاتھ سے ہم کو چھڑا دے گا اور نہیں تو اے بادشاہ! تجھے معلوم ہو کہ ہم تیرے معبودوں کی عبادت نہیں کریں گے اور اُس سونے کی مورت کو جسے تُو نے نصب کیا ہے سجدہ نہ کریں گے.تب نبوکدنضر غصّہ سے بھر گیا اور اُس کے چہرے کا رنگ سدرک اور میسک اور عبیدنجُو پر مبدّل ہوا اور اُس نے حکم دیا کہ بھٹی کی آنچ اُس معمول سے جو اُس کا تھاہفت چند زیادہ کر یں.اور لشکر کے زورآور پہلوانوں کو حکم کیا کہ سدرک اور میسک اور عبیدنجُو کو باندھیں اور جلتی بھٹی میں ڈال دیں.تب وَے اشخاص اپنی قبا اور زیر جامہ اور ٹوپی اور پوشاک سمیت باندھے گئے اور جلتی بھٹی کے بیچوں بیچ میں ڈالے گئے اس لئے کہ بادشاہ کا حکم تاکیدی تھا اور بھٹی کی آنچ نہایت زیادہ ہوئی.آگ کی لَو نے اُن لوگوں کو جنہوں نے سدرک اور میسک اور عبید نجُو کو اُٹھایا تھا ہلاک کیا اور یہ تین شخص یعنی سدرک اور میسک اور عبیدنجُو باندھے ہوئے جلتی بھٹی کے درمیان گِر پڑے.اُس وقت نبوکد نضر بادشاہ سراسیمہ ہوا اور اُس نے جلد اُٹھ کر ارکانِ دولت سے مخاطب ہو کر کہا.کیا ہم نے تین شخصوں کو بندھوا کر جلتی بھٹی میں نہیں ڈلوایا.انہوں نے جواب میں کہا.اے بادشاہ! سچ ہے.اُس نے جواب میں کہا.دیکھو چار شخص کھلے ہوئے آگ کے بیچ پھرتے دیکھتا ہوں اور اُنہیں کچھ ضرر نہ ہوا.اور چوتھے کی صورت خدا کے بیٹے سی ہے.تب نبوکدنضر نے آگ کی جلتی بھٹی کے دروازے پر آکر پکارا کہ اے سدرک اور میسک اور عبید نجُو خدا تعالیٰ کے بندو باہر نکلو اور اِدھر آئو تو سدرک اور میسک اور عبید نجُو آگ کے درمیان سے نکل آئے اور سارے امیروں اور حاکموں اور سر لشکروں اور بادشاہ کے مشیروں نے فراہم ہو کر اُن شخصوں پر نظر کی کہ آگ کی اُن کے بدنوں پر تاثیر نہ ہوئی تھی اور نہ اُن کے سر کا ایک بال جُھلس گیا اور نہ
Page 529
اُن کی پوشاک میں مطلق کچھ فرق ہوا اور نہ آگ سے جلاہٹ کی بُو اُن پر سے معلوم ہوتی تھی.تب بنو کد نضر نے پکار کے کہا کہ سدرک اور میسک اور عبیدنجُو کا خدا مبارک ہو جس نے اپنے فرشتے کو بھیجا اور اپنے بندوں کو جنہوں نے اُس پر توکل کر کے بادشاہ کے حکم کو ٹال دیا ہے اور اپنے بدنوں کو نثار کیا کہ سوا اپنے خدا کے دوسرے معبود کی عبادت اور بندگی نہ کریں چھڑایا ہے اس لئے مَیں حکم کرتا ہوں کہ جو قوم یا گروہ یا اہل لغت سدرک اور میسک اور عبید نجُو کے خدا کے حق میں کوئی نالائق سخن بولیں گے تو اُن کے ٹکڑے ٹکرے کئے جائیںگے.اور اُن کے گھر گھورے بن جائیں گے.کیونکہ کوئی دوسرا خدا نہیں جو اِس طرح چھڑا سکے.تب بادشاہ نے سدرک اور میسک اور عبید نجُو کو صوبہ بابل میں سرفراز کیا.‘‘ (دانی ایل باب ۳) یہ ایک واقعہ ہے جو گزشتہ زمانہ میںہوا.اور جس کومفسرین نے بھی بیان کیا ہے وہ اس میں دانیال کو بھی شامل کر دیتے ہیں مگر یہ اُن کی غلطی ہے.اور اِس غلطی کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ اُس وقت بائیبلیں کثرت سے نہیں تھیںاس لئے غلطی سے انہوں نے دانیال کو بھی اس میں شامل سمجھ لیا.بہرحال یہ ایک واقعہ ہے جو گزشتہ زمانہ میں ہوا.اُس میں ایک بھٹی کا بھی ذکر آتا ہے.یہ بھی آتا ہے کہ اس میں آگ جلائی گئی.یہ بھی آتا ہے کہ اُس میں تین آدمی پھینکے گئے.اور یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ بادشاہ اور اُس کے ساتھی اِس نظارہ کودیکھتے رہے.اس حد تک تو درست ہے لیکن اِس کے واقعات پورے طور پر قرآنی واقعات سے نہیںتھے.کیونکہ قرآن کریم نے اُن کے متعلق یہ نہیں بتایا کہ وہ آگ میں سے زندہ نکل آئے تھے.بائیبل میں چونکہ مبالغہ بھی ہے اس لئے ممکن ہے اتنا حصہ بعد میں بڑھا لیا گیا ہو.اور اِس حد تک بات درست ہو کہ کچھ لوگوں کو محض اس لئے آگ کی بھٹی میں جلا دیا گیا ہو کہ وہ کیوں خدائے واحد پر ایمان لاتے ہیں.قُتِلَ اَصْحٰبُ الْاُخْدُوْدِمیں آئندہ زمانہ میں ہونے والے واقعات کی پیشگوئی ایسا ہر زمانہ میں ہوتا رہا ہے.اور ہر نبی کے وقت دشمنانِ دین کی طرف سے خدا تعالیٰ پر ایمان لانے والوں کو قِسم قِسم کے عذابوں میں مبتلا کیا گیا ہے.لیکن میرا یہ یقین ہے کہ جب اِ س سورۃ کو وَ السَّمَآءِ ذَاتِ الْبُرُوْجِ وَالْیَوْمِ الْمَوْعُوْدِ وَشَاھِدٍ وَّمَشْھُوْدٍ کے الفاظ سے شروع کیا گیا ہے تو شہادت کسی ایسے واقعہ کے متعلق ہی ہوتی ہے جو آئندہ زمانہ میں ہونے والا ہو.قرآن کریم میں تم یہ کہیں نہیں دیکھو گے کہ خدا نے کہا ہو میں سورج اور چاند کو اِس بات کی شہادت کے طور پر پیش کرتا ہوں کہ مَیں نے آدم ؑ بھیجا تھا.یا نوح ؑ بھیجا تھا.یا ابراہیم ؑ اور موسیٰ ؑ کو مبعوث کیا تھا.شہادت ایسے ہی امور کے متعلق
Page 530
پیش کی جاتی ہے جو غیبی ہوں یا آئندہ زمانہ میں رُونما ہونے والے ہوں.پس جبکہ قرآن کریم میںکوئی قسم ایسی نہیں جو ماضی کے واقعات پر کھائی گئی ہو تو بائیبل کے اِس واقعہ کو قُتِلَ اَصْحٰبُ الْاُخْدُوْدِ والی آیت پر چسپاں کرنا قرآنی طریق کے خلاف ہے اور عقل کے بھی خلاف ہے.ایک تاریخی واقعہ جو گزر چکا ہے اُس پر اللہ تعالیٰ کو قَسم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہو سکتی تھی.مَیں اِس کا مُنکر نہیں کہ گزشتہ زمانہ میں بھی کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو.مَیں صرف یہ کہتا ہوں کہ اگر گزشتہ زمانہ میں کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے تو یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ ایسا ہی واقعہ پھر کوئی ہونے والا ہے.پس میرے نزدیک قُتِلَ اَصْحٰبُ الْاُخْدُوْدِ.النَّارِ ذَاتِ الْوَقُوْدِ.اِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُوْدٌ کے ذریعہ ایک دوسری پیشگوئی شروع کی گئی ہے.پہلے یہ بتایا گیا تھا کہ مسیح موعود ؑ ظاہر ہو گا اور اسلام کو غالب کرے گا.چنانچہ اِس کی دلیل یہ دی گئی تھی کہ ماضی شاہد ہے کہ اللہ تعالیٰ احیائِ اسلام کے لئے ہمیشہ مجددین مبعوث کرتا رہا ہے.پس ضروری ہے کہ آئندہ بھی یہ سلسلہ جاری رہے بالخصوص اس لئے کہ ہم ایک موعود کی بعثت کی خبر دے چکے ہیں.اب یہ بتاتا ہے کہ یومِ موعود آسانی سے نہیں آئے گا بلکہ اِس کے لئے مومنوں کو بڑی بھاری قُربانیاں کرنی پڑیں گی.چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یومِ موعود کے متعلق بڑا زور دیا گیا تھا اس لئے ممکن تھا جماعتِ موعود یہ خیال کر لیتی کہ یہ یومِ موعود خود بخود آجائے گا ہمیں اِس کے لئے کسی خاص جدوجہد سے کام نہیں لینا پڑے گا.سو خدا تعالیٰ نے قُتِلَ اَصْحٰبُ الْاُخْدُوْدِ.النَّارِ ذَاتِ الْوَقُوْدِ کے ذریعہ اِس خیال کا ازالہ کر دیا اور بتایا کہ یہ یومِ موعود آئے گا تو سہی مگر تمہیں اپنی جانوں کو اِس راہ میں قربان کرنا پڑے گا اور مخالفین کے جور وستم اور اُن کے بھیانک مظالم کا ایک عرصہ تک تختۂ مشق بننا پڑے گا.اسلام کے زندہ کرنے کے لئے مصائب کا برداشت کرنا ضروری ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بھی جماعت کو بارہا اِس امر کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اسلام اور احمدیت کی ترقی ہم سے موت کا مطالبہ کرتی ہے.اگر ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ بغیر اُن قربانیوں کے جو صحابہؓ نے کیں یا بغیر اُن قربانیوں کے جو سابق انبیاء ؑ کی اُمتیں بجا لائیں ہم اپنے مقصود کو حاصل کر لیں گے تو ہم سے زیادہ احمق اور غلطی خوردہ اور کوئی نہیں ہو سکتا.اسلام اور احمدیت کی ترقی ہماری قربانیوں کے ساتھ وابستہ ہے اور یہی وہ موت ہے جس میں حقیقی زندگی پائی جاتی ہے.چنانچہ آپؑ اسلام اور احمدیت کی ترقی کی پیشگوئی کرتے ہوئے فرماتے ہیں.’’سچائی کی فتح ہو گی اور اسلام کے لئے پھر اُس تازگی اور روشنی کا دن آئے گا جو پہلے وقتوں میں آچکا ہے اور وہ آفتاب اپنے پورے کمال کے ساتھ پھر چڑھے گا جیسا کہ پہلے چڑھ چکا ہے.لیکن ابھی
Page 531
ایسا نہیں.ضرور ہے کہ آسمان اُسے چڑھنے سے روکے رہے جب تک کہ محنت اور جانفشانی سے ہمارے جگر خون نہ ہو جائیں.اور ہم سارے آراموں کو اُس کے ظہور کے لئے نہ کھو دیں اور اعزازِ اسلام کے لئے ساری ذلّتیں قبول نہ کر لیں.اسلام کا زندہ ہونا ہم سے ایک فدیہ مانگتا ہے.وہ کیا ہے؟ ہمارا اِسی راہ میں مرنا.یہی مَوت ہے جس پر اسلام کی زندگی مسلمانوں کی زندگی اور زندہ خدا کی تجلّی موقوف ہے.‘‘ (فتح اسلام روحانی خزائن جلد ۳ صفحہ ۱۰ تا۱۱) اِسی طرح فرماتے ہیں.’’دُنیا کی لذتوں پر فریفتہ مت ہو کہ وہ خدا سے جُدا کرتی ہیں.اور خدا کے لئے تلخی کی زندگی اختیار کرو.وہ درد جس سے خدا راضی ہو اُس لذت سے بہتر ہے جس سے خُدا ناراض ہو جائے.اور وہ شکست جس سے خدا راضی ہو اُس فتح سے بہتر ہے جو موجبِ غضبِ الٰہی ہو.اُس محبت کو چھوڑدو جو خدا کے غضب کے قریب کرے.اگر تم صاف دل ہو کر اُس کی طرف آ جائو تو ہر ایک راہ میں وہ تمہاری مدد کرے گااور کوئی دشمن تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا.خدا کی رضا کو تم کِسی طرح پا ہی نہیں سکتے جب تک تم اپنی رضا چھوڑ کر اپنی لذات چھوڑ کر.اپنی عزت چھوڑ کراپنا مال چھوڑ کر.اپنی جان چھوڑ کر اُس کی راہ میں وہ تلخی نہ اٹھائو جو مَوت کا نظارہ تمہارے سامنے پیش کرتی ہے.لیکن اگر تم تلخی اٹھا لو گے تو ایک پیارے بچے کی طرح خدا کی گود میں آ جائو گے اور تم اُن راستبازوں کے وارث کئے جائو گے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں.‘‘ ’’یہ مت خیال کرو کہ خدا تمہیں ضائع کر دے گا تم خدا کے ہاتھ کا ایک بیج ہو جو زمین میں بویا گیا.خدا فرماتا ہے کہ یہ بیج بڑھے گااور پُھولے گا اور ہر ایک طرف سے اس کی شاخیں نکلیں گی اور ایک بڑا درخت ہو جائے گا.پس مبارک وہ جو خدا کی بات پر ایمان رکھے.اور درمیان میں آنے والے ابتلائوں سے نہ ڈرے.کیونکہ ابتلائوں کا آنا بھی ضروری ہے تا خدا تمہاری آزمائش کرے کہ کون اپنے دعویٔ بیعت میں صادق اور کون کاذب ہے.وہ جو کسی ابتلاسے لغزش کھائے گا وہ کچھ بھی خدا کا نقصان نہیں کرے گا اور بدبختی اُس کو جہنم تک پہنچائے گی.اگر وہ پیدا نہ ہوتا تو اُس کے لئے اچھا تھا.مگر وہ سب لوگ جو اخیر تک صبر کریں گے اور اُن پر مصائب کے زلزلے آئیں گے اور حوادث کی آندھیاں چلیں گی اور قومیں ہنسی اور ٹھٹھا کریں گی اور دُنیا اُن سے سخت کراہت کے ساتھ پیش آئے
Page 532
گی وہ آخر فتحیاب ہوں گے اور برکتوں کے دروازے اُن پر کھولے جائیں گے.خدا نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ مَیں اپنی جماعت کو اطلاع دوں کہ جو لوگ ایمان لائے ایسا ایمان جو اُس کے ساتھ دُنیا کی ملونی نہیں اور وہ ایمان نفاق یا بزدلی سے آلودہ نہیں اور وہ ایمان اطاعت کے کسی درجہ سے محروم نہیںایسے لوگ خدا کے پسندیدہ لوگ ہیں.اور خدا فرماتا ہے کہ وہی ہیں جن کا قدم صدق کا قدم ہے.‘‘ (الوصیت روحانی خزائن جلد ۲۰ صفحہ ۳۰۷،۳۰۸) آپؑ نے لوگوں کی ایسی غلط فہمی کا بھی ازالہ کیا کہ اسلام اور احمدیت کو آپ ہی آپ ترقی حاصل ہو جائے گی.اِس کے لئے کسی قربانی یا جدّوجہد کی ضرورت پیش نہیں آئے گی.چنانچہ آپؑ نے فرمایا.’’یاد رکھو! ہمارے پاس کوئی ایسی پھونک نہیں جس سے کوئی شخص یک دفعہ ابدال میں داخل ہو جائے سب انبیاء ؑکا اِس پر اتفاق ہے کہ ترقی ٔ مدارج کے لئے آزمائش ضروری ہے.اور جب تک کوئی شخص آزمائش اور امتحان کی منازل طَے نہیں کرتا دیندار نہیں بن سکتا.یہ قاعدہ کی بات ہے کہ دکھ کے بعد ہی ہمیشہ راحت ہوا کرتی ہے.یاد رکھو جو شخص خدا کی راہ میں دُکھ اور مصیبت برداشت کرنے کے لئے تیار نہیں وہ کاٹا جائے گا.‘‘ ’’صحابہ رضی اللہ عنہم کے زمانہ پر غورکرو کہ انہوں نے دین کی خاطر کیسے کیسے مصائب اُٹھائے.اور کن کن دُکھوں میں وہ مبتلاء ہوئے.نہ دن کو آرام کیا نہ رات کو.خدا کی راہ میں ہر ایک مصیبت کو قبول کیا اور جان تک قربان کر دی.‘‘ ’’یاد رکھو! جب تک اخلاص اور صدق سے کوشش نہیں کرو گے کچھ نہیں بنے گا.بہت آدمی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ یہاںسے تو بیعت کر جاتے ہیں مگر گھر میں جا کر جب تھوڑی سی بھی تکلیف آئی یا کسی نے دھمکایا یا حقہ پانی بند کرنا چاہا تو جھٹ مُرتد ہو گئے.ایسے لوگ ایمان فروش ہوتے ہیں.صحابہؓ کو دیکھو کہ انہوں نے تو دین کی خاطر اپنے سر کٹوا دیئے تھے اور جان ومال سب خدا کی راہ میں قربان کرنے کے لئے تیار رہتے تھے.کِسی دشمن کی دشمنی کی اُنہیں پرواہ تک بھی نہ تھی.وہ تو خدا کی راہ میں سب طرح کی تکالیف اُٹھاتے اور ہر طرح کے دُکھ برداشت کرنے کے لئے ہر وقت تیار ہتے تھے.اور انہوں نے اپنے دلوں میں فیصلہ کیا ہوا تھا.ایمان وہ ہے کہ سارا جہان مخالف ہو جائے.ہر
Page 533
طرف سے سانپ اور بچھّو کاٹیں.ہر گوشہ سے بجلی گرے.ہر جگہ سے دُکھ ہو مگر ایمان متزلزل نہ ہو.‘‘ (بدر ۱۷ ؍اکتوبر۱۹۰۷صفحہ ۸ و ۹) یہ وہ قربانی کی روح ہے جو جماعت احمدیہ میں پیدا ہونی چاہیے.اور یہی وہ روح ہے جس کے قیام کے ساتھ قوموں کی زندگی وابستہ ہوتی ہے.اللہ تعالیٰ نے اِس سورۃ میں ایک طرف تو منکرین کو توجہ دلائی ہےکہ تم بارہ صدیوں تک خدا تعالیٰ کے مجددین کو مانتے چلے آئے تھے اب تیرہویں مقام پر آکر تمہیں کیا ہو گیا کہ جب وہ موعود ظاہر ہوا جس کی خبر ہم دیتے چلے آئے تھے تو تم نے اُس کا انکار کر دیا اور دوسری طرف مومنوں سے کہا ہے کہ یاد رکھو تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ میں جلنا پڑے گا تب اسلام کی شان وشوکت کا دن طلوع کرے گا.احمدیت کی سخت مخالفت کی پیشگوئی پس اِن آیات میں اُس مخالفت کی شدّت کا نقشہ کھینچا گیا ہے جو احمدیت کی آئندہ زمانہ میں ہونے والی ہے.اِذْھُمْ عَلَیْھَا قُعُوْدٌ سے ظاہر ہوتا ہے کہ مومنوں کو عذاب دے دے کر دشمن مزہ اٹھائیں گے.دو قسم کی تعذیبیں تعذیبیں دو قسم کی ہوتی ہیں.ایک تعذیب وہ ہوتی ہے جس کے بعد دل میں رحم کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیںچنانچہ مجرموں کو پھانسی پر لٹکایا جاتا ہے تو مجسٹریٹ اور سپاہی وغیرہ افسوس بھی کرتے جاتے ہیں مگر ایک تعذیب وہ ہوتی ہے جس کے بعد عذاب دینے والا خوشی محسوس کرتا ہے کہ مَیں نے جو کچھ کیا بہت اچھا کیا.فرماتا ہے یہ معذّب تو ہوں گے مگر ساتھ ہی خوش ہوں گے کہ ہم نے بہت اچھا کام کیا ہے.گویا جلوس نکلیں گے اور اپنے اِس فعل پر بڑی خوشی منائی جائے گی جیسے حضرت صاحبزادہ عبداللطیف صاحب شہیدؓ پر پتھرائو کیا گیا مگر کسی کو رحم نہ آیا.بادشاہ اور اُس کے درباری سب اکٹھے تھے اور کہتے تھے کہ اِسے خوب پتھر مارو.گویا عذاب دینے کے لئے وہ اِس طرح خوش خوش اکٹھے ہوئے جیسے کوئی میلہ ہو رہا ہے.وَ هُمْ عَلٰى مَا يَفْعَلُوْنَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ شُهُوْدٌ.شَھُوْدٌ شَاھِدٌ کی جمع ہے اور شَھِدَ یَشْھَدُ شُھُوْدًا کے معنے ہوتے ہیںحَضَـرَ وہاں حاضر ہوا.دوسرے معنے ہوتے ہیں اِطَّلَعَ عَلَیْہِ کسی امر سے واقف اور آگاہ ہوا.یہاں شُھُوْدٌ کے معنے واقفوں کے بھی ہیں اور حاضر ہونے والوں کے بھی.اور مطلب یہ ہے کہ وہ جانتے ہوئے کہ مومن بے گناہ ہیں اُنہیں عذاب اور دکھ دیں گے.اسی طرح یہ معنے بھی ہیں کہ وہ عذاب دینے کے وقت خود بھی سامنے کھڑے ہوں گے اور اُن کے عذاب کا تماشہ دیکھیں گے اور اُن پر انہیںرحم نہ آئے گا.
Page 534
اِذْھُمْ عَلَیْھَا قُعُوْدٌسے عذاب دینے والوں کے متعلق دو باتوں کا اظہار اِذْھُمْ عَلَیْھَا قُعُوْدٌ سے دو باتیں ظاہر ہوتی ہیں.اوّل یہ کہ وہ میلہ لگائیں گے.لوگوں کا اجتماع کریں گے اور سب کی موجودگی میں اُن کو عذاب دیں گے.دوسرےؔ یہ کہ یہ تعذیب متواتر چلے گی.کیونکہ کسی چیز پر بیٹھ جانا یہ ایک محاورہ ہے جس کے معنے اس کام کو متواتر کرتے چلے جانے کے ہوتے ہیں.ہماری زبان میں بھی کہتے ہیں کہ تم تودھرنا مار کر بیٹھ رہے ہو.مطلب یہ کہ پیچھا ہی نہیں چھوڑتے.اِسی طرح فرماتا ہے جہاں اِن کی مخالفتیں دیدہ دانستہ ہوں گی اور یہ سمجھتے ہوئے ہوں گی کہ وہ جھوٹ اور فریب سے کام لے رہے ہیں وہاں ان مخالفتوں کا ایک لمبا سلسلہ ہو گا اور متواتر اُن کی طرف سے دُکھ دینے والے واقعات کا اعادہ ہوتا رہے گا.اِس زمانہ میں ہم احمدیت کے مخالفین کو دیکھتے ہیں تو اُن کی عملی حالت ہمیںیہی نظر آتی ہے.وہ خوب جانتے ہیں کہ بات اسی طرح ہے جس طرح احمدیت پیش کرتی ہے مگر محض اس لئے کہ جماعت احمدیہ کی طرف سے پیش کی جاتی ہے اس کی مخالفت کرنا وہ ضروری سمجھتے ہیں.اگر آج ہم کہہ دیتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مقام بلند حاصل کیا وہ اپنے زورِ عمل سے حاصل کیا تو تمام غیر احمدی شور مچانا شروع کر دیتے ہیں کہ احمدی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کی ہتک کرتے ہیں حالانکہ اس میں ہتک کی کوئی بات نہیں بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت اِسی عقیدہ سے ظاہر ہوتی ہے.پہلے مَیں نے سمجھا تھا کہ شاید لوگ ہمارے لٹریچر کو نہیں دیکھتے اور سنی سنائی باتوں کی وجہ سے شور مچا دیتے ہیں.مگر تھوڑے ہی دن ہوئے ایک دوست نے مجھے ایک اخبار کا کٹنگ بھیجا جس میں میرے خطبہ کا حوالہ درج تھا اور پھر لکھا تھا کہ دیکھو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیسی سخت ہتک ہے کہ کہا جاتا ہے آپؐ نے زورِ عمل سے اپنا مقام حاصل کیا صرف خدا تعالیٰ کی موہبت سے ایسا نہیں ہوا.گویا بات سمجھ لی مگر پھر بھی مخالفت کرنا ضروری سمجھا تا کہ لوگوں میں ہمارے خلاف جوش اور اشتعال پیدا ہو تو فرماتا ہے وَ هُمْ عَلٰى مَا يَفْعَلُوْنَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ شُهُوْدٌ وہ اپنے افعال کے ناروا ہونے پر خود گواہ ہوں گے.وہ ظلم کر رہے ہوں گے اور جانتے ہوں گے کہ ظلم کر رہے ہیں وہ جھوٹ اور فریب سے کام لے رہے ہوں گےاور اُن کے نفوس جانتے ہوں گےکہ وہ دھوکا اور فریب کر رہے ہیں مگر پھر بھی مخالفت کریں گے.
Page 535
وَ مَا نَقَمُوْا مِنْهُمْ اِلَّاۤ اَنْ يُّؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ الْعَزِيْزِ اور وہ ان سے صرف اس لئے دشمنی کرتے تھے کہ وہ غالب (اور سب تعریفوں کے مالک) اللہ پر کیوں الْحَمِيْدِۙ۰۰۹الَّذِيْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ١ؕ وَ اللّٰهُ عَلٰى ایمان لائے.وہ (اللہ) جس کے قبضہ میں آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے اور (یہ نہیں سوچتے کہ) اللہ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌؕ۰۰۱۰ ہر چیز (کے احوال سے) واقف ہے.حَلّ لُغَات.نَقَمُوْا.نَقَمُوْا نَقَمَ سے جمع کا صیغہ ہے.اور نَقَمَ مِنْہُ کے معنے ہوتے ہیں.اَنْکَرَہٗ عَلَیْہِ وَعَابَہٗ وَکَرِہَہٗ اَشَدَّ الْکَرَاہَۃِ لِسُوْئِ فِعْلِہٖ.اُس کی بات کو ناپسند کیا.اُس پر عیب لگایا اور اُس کے بُرے فعل کی وجہ سے اُس سے شدید کراہت اور ناپسندیدگی کا اظہار کیا.نیز کہتے ہیں نَقَمَ مِنْہُ اور معنے ہوتے ہیں عَاقَبَہٗ اُس کو سزا دی.(اقرب) تفسیر.فرماتا ہے اُن کی کوئی بات اُن کو حقیقتاً ناپسند نہیں ہو گی اور نہ اُن پر وہ کوئی حقیقی عیب لگا سکیں گے.سوائے اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر کیوں ایمان لائے.یوں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوں گے مگر فرق یہ ہو گا کہ یہ لوگ عزیز اور حمید خدا پر ایمان رکھتے ہوں گے.ایک زندہ اور قادر خدا کو مانتے ہوں گے مگر وُہ لوگ ایک مُردہ خدا کو ماننے والے ہوں گے.پس چونکہ موعود کے اتباع اُن کے مردہ خدا کو نہیں مانتے ہوں گے بلکہ ایک عزیز اور حمید خدا کے قائل ہوں گے.اس لئے وہ لوگ اُن کی مخالفت کریں گے.اُن کو طرح طرح کے دُکھ دینے کی کوشش کریں گے اور کہیں گے کہ اُن لوگوں نے ایک نیا دین بنا لیا ہے.حالانکہ وہ خدائے حمید کو پیش کر رہے ہوں گے اور یہ لوگ خدائے حمید پر طرح طرح کے عیوب لگا رہے ہوں گے.مثلًا یہی کہ حضرت عیسٰی علیہ السلام آسمان پر زندہ ہیں یا یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یونہی افضل الرسل بنا دیا.ورنہ اگر اعمال کا سوال ہوتا تو ممکن تھا کہ کوئی اور شخص آپؐ سے آگےنکل جاتا ہے.چنا نچہ دیکھ لو وہ تمام عقائد جن کی وجہ سے جماعت احمدیہ پر اعتراض کیا جاتا ہے ان میں سے ایک ایک عقیدہ وہ ہے جو خدا کی حمد ثابت کرنے والا ہے مگر ان لوگوں کے سارے عقیدے وہ ہیں
Page 536
جو خدا تعالیٰ کی ہتک کا موجب ہیں.یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں صرف اِلَّآ اَنْ یُّؤْمِنُوْا نہیں فرمایا.بلکہ اِلَّاۤ اَنْ يُّؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ فرمایا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو وہ لوگ بھی مانتے ہوں گے فرق صرف یہ ہو گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو غیر عزیز اور غیر حمید مانتے ہوں گے.اور یہ لوگ خدا تعالیٰ کو العزیز اور الحمید قرار دیتے ہوں گے.اور یہی اختلاف تمام عداوت کی بنیاد ہو گا.الَّذِيْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ فرماتا ہے اُن کو یہ بھی ڈر نہیں آئے گا کہ یہ لوگ اُس خدا پر ایمان اور یقین رکھنے والے ہیں جو آسمانوں اور زمینوں کا خدا ہے.جو لوگ آسمانوں اور زمینوں کے خدا کی عزت کو قائم کرنے کیلئے کوشش کریں گے.جو لوگ آسمانوں اور زمینوں کے خدا کی حمد کو قائم کرنے کی کوشش کریں گے.یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ خُدا اُن پر لوگوں کو ظلم کرتے دیکھے اور وہ خاموش رہے.دُنیا میں ذلیل سے ذلیل اور حقیر سے حقیر انسان بھی اپنی عزت کرنے والے کا احترام کرتا ہے پھر کس طرح ہو سکتا ہے کہ یہ آسمان اور زمین کے مالک خدا کی عزت قائم کر رہے ہوں.اُس کی حمد قائم کر رہے ہوں.اور پھر دُشمن اُن کو تباہ وبرباد کرنے میں کامیاب ہو جائیں.وہ لوگ غور کریں کہ کیااُن کے ظلموں کو دیکھ کر آسمانوں اور زمینوں کے خدا کی غیرت نہیں بھڑکے گی.اور کیا وہ اپنے غضب کی چکّی میں اُن کو پیس نہیں ڈالے گا.وَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ.فرماتا ہے یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ لوگ جانتے بُوجھتے ہوئے ظلم کرتے ہیں.مگر اِن کو یہ گھمنڈ ہے کہ پبلک ہمارے ساتھ ہے یہ لوگ ہمارا کیا بگاڑ سکتے ہیں اُن کو پتہ نہیں کہ ہم بھی ان کے نگران اور محافظ موجود ہیں.اگر ان کو یہ گھمنڈ ہے کہ ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھنے والے دُنیا میں بہت لوگ موجود ہیں جو ہمارے مظالم کو بھی اچھا قرار دیں گے تو کیا وہ اتنی بات نہیں سوچتے کہ وہ لوگ جو میری عزت کو قائم کرنے والے ہیں.میری حمد کو قائم کرنے والے ہیں وہ میری آنکھوں کے سامنے اِس طرح مظالم کا نشانہ بنائے گئے تو کیا مَیں خاموش رہوں گا.مَیں یقیناً اُن کی مدد کے لئے اُتروں گا اور مظالم کرنے والوں کو اپنے غضب کا نشانہ بنا دوں گا.
Page 537
اِنَّ الَّذِيْنَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوْبُوْا وہ لوگ جنہوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو عذاب میں مبتلا کیا پھر (اپنے فعل سے) توبہ بھی نہ کی اُنہیں فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَ لَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيْقِؕ۰۰۱۱ یقیناً جہنّم کا عذاب ملے گا اور (اِس دُنیا میں بھی) اُنہیں (دل کو) جلا دینے والا عذاب ملے گا.حَلّ لُغَات.فَتَنُوْا.فَتَنُوْا فَتَنَ سے جمع کا صیغہ ہے.اور فَتَنَ الشَّیْءَ کے معنے ہوتے ہیں.اَحْرَقَہٗ.اُس کو جلا دیا (اقرب) پس اِنَّ الَّذِیْنَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِیْنَ کے معنے ہوئے وہ لوگ جنہوں نے مومنوں کو آگ میں جلایا.تفسیر.الٰہی جماعتوں کو دکھ دینے کا نتیجہ چونکہ کفار نے مومنوں کے لئے ایک بھڑکتی ہوئی آگ تیار کی تھی جس میں اُن کو ڈالا گیا تھا اس لئے فرماتا ہے.یقیناً وہ لوگ جو مومن مَردوں اور عورتوں کو عذاب دیتے ہیں اُن کے لئے جہنم کا عذاب ہو گا.یہاں ظاہری اور باطنی دونوں قِسم کی آگ مراد ہو سکتی ہے.ظاہری اِس لحاظ سے کہ وُہ اُن کے جسموں کو دُکھ دیں گے.اور باطنی اِس لحاظ سے کہ وہ ایسے ایسے جھوٹے الزام لگائیں گے جن کو سُن کر اُن کے دل جل جائیں گے.اور وہ حیران ہوں گے کہ ہم کیا کریں.فرماتا ہے وہ لوگ جو مومن مَردوں اور عورتوں کو جلاتے ہیں.اُن کی طرف طرح طرح کی جھوٹی باتیں منسوب کرتے ہیں.اُن کا دل دکھانے کے لئے ہر قِسم کی تدابیر اختیار کرتے ہیں وہ مت سمجھیں کہ ہماری گرفت سے وہ بچ سکیں گے.چنانچہ آج کل ہماری جماعت کے خلاف جس رنگ میں فتنہ پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے وہ اس کا ایک کھلا اور واضح ثبوت ہے.غیر احمدی ہمارا دل یہ کہہ کر زخمی کرتے ہیں کہ ہم نعوذ باللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے(تحفہ قادیانیت جلد اول صفحہ ۶۷۱ از محمد یوسف لدھیانوی).اور پیغامی یہ کہہ کر ہمیں دُکھ دیتے ہیں کہ ہم کلمہ طیبہ کو نعوذ باللہ منسوخ سمجھتے ہیں.(ہفت روزہ پیغام صلح ۲۹ اگست ۱۹۷۳ صفحہ ۳) حالانکہ ہم جو کچھ کہتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور آپؐ کے جلال کے اظہار کے لئے کہتے ہیں.کوئی ایسی بات اپنی زبان سے نہیں نکالتے جو آپؐ کی شان کو کم کرنے والی اور آپؐ کی عزت کو بٹّہ لگانے والی ہو.پس فرماتا ہے وہ لوگ جو مومن مَردوں اور مومن عورتوں کے بدنوں کو یا ان کے دلوں کو یا اُن کے گھروں کو جلاتے ہیں اور پھر اپنے اس فعل سے توبہ نہیں کرتے ہم ان کو عذاب میں مبتلا کریں گے.ہاں اگر کوئی شخص
Page 538
توبہ کرے تو پھر خواہ کتنا بڑا گناہ کر چکا ہو اُس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اُسے معاف فرما دیتا ہے.پس فرمایا گو اُنہوں نے بڑا گناہ کیا ہے لیکن اگر پھر بھی وہ توبہ کر لیں تو خواہ کوئی گناہ اُن سے سرزد ہو چکا ہو ہم اُن کو معاف کر دیں گے.لیکن اگر وہ توبہ نہیں کریں گے.تو یاد رکھیں کہ فَلَھُمْ عَذَابُ جَھَنَّمَ وَلَھُمْ عَذَابُ الْحَرِیْقِ جس طرح انہوں نے مومنوں کے دلوں کو بھی جلایا تھا اور اُن کے جسموں کو بھی جلایا تھا اُسی طرح اُن کو بھی دو قِسم کا عذاب دیا جائے گا.ظاہری بھی اور باطنی بھی.عذابِ جہنّم ظاہری ہے اور عذاب الحریق باطنی ہے.یا عذاب الحریق ظاہری ہے اور عذاب جہنّم باطنی ہے.بہرحال ان دو قسم کے عذابوں کے مقابلہ میں جو انہوں نے مومنوں کو دئیے اُن کو بھی دو قسم کے عذاب دئیے جائیں گے.اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ (اور وہ) جو ایمان لائے اور (اس کے ساتھ اس کے) مناسبِ حال عمل بھی کئے اُنہیں باغات ملیں گے جن کے نیچے مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ١ۣؕ۬ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيْرُؕ۰۰۱۲ نہریں بہتی ہوں گی.(اور) یہی تو بڑی کامیابی ہے.حَلّ لُغَات.اَلْفَوْزُ.اَلْفَوْزُ اَلظَّفَرُ بِالْخَیْرِ بہترین مقصود پا کر کامیاب ہونا.نیز اِس کے معنے ہیں اَلنَّجَاۃُ.نجات.(اقرب) تفسیر.عمل صالح کا مطلب یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمالِ صالحہ بجا لائے.عمل صالح کے معنے ایسے اعمال کے ہیں جو مطابقِ حالات ہو.یہ معنے اتنے اہم اور اس قدر ضروری ہیں کہ اِن پر جس قدر بھی زور دیا جائے کم ہے.کیونکہ مسلمانوں کی تمام کامیابی اور ترقی کا دارومدار انہی معنوں پر ہے.اگر حالات کے مطابقِ عمل کیا جائے گا تو وہ یقیناً عمل صالح ہو گا.اور اگر حالات کی مطابقت کا خیال نہیں رکھا جائے گا تو وہ عمل غیر صالح ہو گا.مثلًاشراب اسلام سے پہلے حرام نہیں تھی.صرف اسلام نے اس کو قطعی طور پر حرام قرار دیا ہے.اِس صورت میں صلاحیت کے محض اتنے معنے نہیں ہوں گے کہ انسان شراب نہ پئے بلکہ صلاحیت کے یہ معنے ہوں گے کہ جس زمانہ میں خدا نے کِسی فعل سے روکا ہے اُس زمانہ میں اُس فعل سے رُک جائے اگر شراب سے روکا ہے تو رک جائے اور اگر نہیں روکا تو بیشک نہ رُکے.اِسی وجہ سے گو اسلام کو پہلی شرائع سے کئی امور میں اختلاف ہے مگر چونکہ اُن شریعتوں
Page 539
میں شراب قطعی طور پر حرام نہیں تھی اِس لئے اُن اُمّتوں میں جن لوگوں نے شراب استعمال کی تھی انہوں نے عملِ غیر صالح نہیں کیا تھا.بلکہ اُس زمانہ کے حالات کے لحاظ سے وہ عملِ صالح ہی تھا.پس ایمان لانے اور عملِ صالح کرنے والوں کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اُن کو جنّات ملیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی.جس طرح کفار کے متعلق ذکر کیا گیا تھا کہ اُ ن کو دو قسم کے عذاب دئیے جائیں گے اسی طرح یہاں مومنوں کے متعلق فرماتا ہے کہ اُن کو دو قسم کے انعامات دئیے جائیںگے.اوّلؔ باغات ملیں گے جو اوپر سے سایہ کرنے والی چیز ہیں.دومؔ.اُن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی.گویا اوپر سے بھی ٹھنڈک ہو گی اور نیچے سے بھی ٹھنڈک ہوگی.ظاہر میں بھی راحت ہوگی اور باطن میں بھی راحت ہو گی.لوگوں میں بھی عزت ہو گی اور خدا کے حضور بھی عزت ہو گی.جَنّٰتٌ تَجْرِیْ مِنْ تَحْتِھَا الْاَنْھٰرُکے دو معنی لَھُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِیْ مِنْ تَحْتِھَا الْاَنْھٰرُ کے دومعنے ہیں.اوّلؔ یہ کہ باغوں کا سایہ ایسا ہو گا جو کِسی جگہ سے ٹوٹے گا نہیں.اُن کی شاخیں آپس میں ملتی چلی جائیں گی.دو درختوں میں ایسا فاصلہ نہیں ہو گا کہ سایہ الگ الگ ہو جائے بلکہ اُس سائے کا ایک سلسلہ ہو گا جس میں کوئی انقطاع واقع نہیں ہو گا.اسی طرح ان کے نیچے جو نہریں بہتی ہوں گی ان کے کسی حصّہ پر بھی دُھوپ نہیں پڑے گی بلکہ سایہ کے مسلسل ہونے کی وجہ سے وہ نہریں بھی اوّل سے آخر تک سایہ کے نیچے ہوں گی.گویا رحمت کے کمال کی طرف ان الفاظ میں اشارہ کیا گیا ہے.دوسرےؔ لَھُمْ میں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ وہ باغات ا ن کی ملکیّت ہوں گے اور وہ نہریں اُن باغات سے وابستہ ہوں گی.یوں تو سرگودھا اور لائلپور وغیرہ میںبھی نہریں ہیں مگر وہ مالکانِ اراضی کی نہیں بلکہ گورنمنٹ کی ہیں.لیکن وہاں جو نہریں ملیں گی وہ جنت کے ساتھ ہوں گی.مِنْ تَحْتِھَا کا یہی مطلب ہے کہ اِس جنت کی نعمتوں کے ضمن میں یہ نہریں ہوں گی.یعنی جس کے باغات ہوں گے اُسی کی نہریں ہو ں گی.اس لئے ایک معنے تو یہ ہیں کہ اُس جنّت کی تمام نعمتیں مالک کے اپنے اختیار میں ہوں گی.دوسرے ؔ یہ کہ وہ بڑی وسیع جنّت ہو گی کیونکہ نہر دو دچار گھمائوں میں نہیں چلتی بلکہ پچاس پچاس ساٹھ ساٹھ بلکہ دو دو ہزار میل تک نہریں چلتی چلی جاتی ہیں.پس مِنْ تَحْتِھَا الْاَنْھٰرُ کہہ کر بتا دیا کہ جنّت کا بدلہ بڑا وسیع ہو گا.غرض اِن آیات میں ایک طرف تو اِس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جنّتیوں کو ظاہری نعمت بھی ملے گی اور قلبی نعمت بھی ملے گی.دوسرےؔ یہ بتایا کہ اُن کی ترقی کے جو سامان ہوں گے وہ اُن کے قبضہ اور اختیار میں ہوں گے.تیسرےؔ یہ کہ وہ سامان نہایت وسیع ہوں گے.
Page 540
اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيْدٌؕ۰۰۱۳ یقیناً تیرے رب کی گرفت سخت ہوا کرتی ہے.حَلّ لُغَات.بَطَشٌ بَطَشَ بِہٖ بَطْشًا کے معنے ہوتے ہیں اَخَذَہٗ بِالْعَفْفِ.اِس کو سختی سے گرفت کی.نیز اس کے معنے ہیں تَنَاوَلَہٗ بِالشِّدَّۃِ عِنْدَ الصَّوْلَۃِ حملہ کرتے وقت سختی سے اُسےپکڑا.اَخَذَ اَخْذًا شَدِیْدًا فِیْ کُلِّ شَیْءٍ.کسی چیز کو سختی سے پکڑا (اقرب) پس اَلْبَطْشُ کے معنے ہوں گے.سختی سے گرفت کرنا.تفسیر.فرماتا ہے.مومنوں کو دُکھ تودئیے جائیں گے مگر خدا کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے.حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کا بھی الہام ہے کہ وَاِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِیْنَ (تذکرۃ الہام ۲۱ اگست ۱۹۰۶ صفحہ ۶۱۱،الحکم ۲۴؍ اگست ۱۹۰۶ صفحہ ۱)یعنی جب تم گرفت کرو گے تو سختی سے کرو گے.پس بے شک وہ مومنوں کوبڑا دُکھ دیں گے.مگر یاد رکھیں خدا کی گرفت بھی بڑی سخت ہے.اِنَّهٗ هُوَ يُبْدِئُ وَ يُعِيْدُۚ۰۰۱۴ (کیونکہ) وہ وہی تو ہے (جو عذاب دینا) شروع کرتا ہے اور پھر اسےبار بار چکر دیتا ہے.تفسیر.يُبْدِئُ وَ يُعِيْدُ کا مطلب خدا پہلی بار بھی پیدا کرتا ہے.اور دوبارہ بھی وہی لَوٹاتا ہے.مطلب یہ کہ خدا ہی ہے جو اِس دنیا میں بھی اُن کو عذاب دے گااور آخرت میں بھی ان کو عذاب دے گا.گویا يُبْدِئُ وَ يُعِيْدُ کے یہ معنے ہیں کہ یُبْدِیُٔ الْعَذَابَ فِی الدُّنْیَا وُیُعِیْدُھَا فِی الْاٰخِرَۃِ.وَ هُوَ الْغَفُوْرُ الْوَدُوْدُۙ۰۰۱۵ اور (اس کے ساتھ ہی) وہ بے انتہاء بخشنے والا اور بے انتہا ءمحبت کرنے والا بھی ہے.تفسیر.غفور اور ودود دو صفات اکٹھی لا کر عیسائیت کی تردید اور وہ بہت بخشنے والا اور محبت کرنے والا ہے.یہاں چونکہ عیسائیت کا ذکر ہے اور عیسائی خدا کو بخشنے والا قرار نہیں دیتے لیکن خدا کو محبت کرنے والا وجود ضرور قرار دیتے ہیں.اس لئے خدا نے غفور اور ودُود دونوں الفاظ کو اس جگہ اکٹھا کر دیا ہے.کہ یہ
Page 541
عجیب بات ہے کہ اِدھر وہ لوگوں کے گناہوں کو بخشتا نہیں اور اُدھر یہ کہا جاتا ہے کہ خدا محبت ہے.حالانکہ غفور اور ودُود ہمیشہ اکٹھے ہوتے ہیں.جو غفور ہو گا ضرور ہے کہ وہ ودُود ہو اور جو ودُود ہو گا ضرور ہے کہ وہ غفور ہو.یہاں یہ دونوں صفات اکٹھی کر کے عیسائیت کے اِس عقیدہ کی خدا تعالیٰ نے تردید کر دی ہے کہ لوگوں کے گناہوں کو بخشنا اُس کے عدل کے خلاف ہے.ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيْدُۙ۰۰۱۶ (وہ) بزرگ عرش کا مالک (ہے).تفسیر.فرماتا ہے وہ عرش والا ہے.اور بڑی بزرگی والا ہے.یہاں ذوالعرش اس لئے کہا گیا ہے کہ عیسائی دُنیا نے ایک وقت یہ دُعاشروع کی جو اپنی غلط فہمی سے اب تک کرتے چلے آتے ہیں.کہ ’’اے خدا تیری بادشاہی آئے.تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو.‘‘ (متی باب ۶ آیت۱۰)اُنیس سو سال اُن کو یہ دُعا کرتے ہوئے گذر گئے مگر اُن کے نزدیک اب تک خدا کی بادشاہت آسمان سے زمین پر نہیں آئی.فرماتا ہے اے عیسائیو! تم یہ کیا کر رہے ہو وہ خدا تو عرش والا ہے اور مجد والا ہے اُنّیس سو سال پہلے اگر اُس نے تمہیں یہ دُعا سکھائی تھی اور پھر اُنیس سو سا ل تک اُس نے اِس دعا کو نہ سنا اور زمین پر خدا کی بادشاہت نہ آئی تو وہ ذوالعرش المجید کس طرح رہا.حالانکہ وہ ذوالعرش ہے.وہ بڑی بزرگی کا مالک ہے.وہ جب کہتا ہے کہ اُس کی بادشاہت زمین پر آجائے تو پھر وہ آنے سےرُکا نہیںکرتی.چنانچہ خدا کی بادشاہت آسمان سے زمین پر پہلے مسیح ناصری ؑ کے ذریعہ آئی پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ آئی اور اب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعہ خدا کی بادشاہت تیسری بار آسمان سے زمین پر آگئی ہے مگر وہ ابھی تک یہی دُعا مانگتے چلے جا رہے ہیں کہ اے خدا جس طرح تیری بادشاہت آسمان پر ہے اسی طرح زمین پر آوے.فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُؕ۰۰۱۷ جس بات کا ارادہ کرے اُسے کر کے رہنے والا ہے.تفسیر.وہ جس کام کا ارادہ کرلے اُسے کر کے رہتا ہے مگر تم یہ کہتے ہو اُس نے اپنی بادشاہت آسمان سے
Page 542
زمین پر لانے کا ارادہ تو کیا تھا مگر اب تک وہ اپنے اِس ارادہ کو پُورا نہیں کر سکا حالانکہ پہلا مسیح ؑ آیا اور اُس کے ذریعہ خدا کی بادشاہت زمین پر آگئی پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اُ ن کے ذریعہ خدا کی بادشاہت زمین پر آگئی اور اب تیسری دفعہ پھر مسیح موعودؑ کے ذریعہ خدا کی بادشاہت آسمان سے زمین پر آ گئی ہے مگر تم ابھی وہیں بیٹھے یہ دعا کر رہے ہو کہ اے خدا تیری بادشاہت جس طرح آسمان پر ہے اُسی طرح زمین پر بھی آئے.هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ الْجُنُوْدِۙ۰۰۱۸فِرْعَوْنَ وَ ثَمُوْدَؕ۰۰۱۹ کیا تمہیں (دشمنان صداقت کے) لشکروں کی خبر نہیں ملی.(یعنی) فرعون اور ثمود کے لشکروں کی.تفسیر.فِرْعَوْنَ وَثَمُوْدُ.جُنُوْد کا بدل ہے.کہ کیا تمہیں لشکروں کی خبر پہنچی ہے.اِس کے بعد اُن جنود کے سرداروں کا نام لے لیا کہ وہ لشکر جو فرعون اور ثمود کے تھے.مطلب یہ کہ یہ کوئی چُھپی ہوئی بات نہیں کہ ہم نے اُن دشمنوں سے کیا کیا تھا بلکہ یہ بالکل ظاہربات ہے.پھر اگر تمہیں فرعون اور ثمود کے لشکروں کی بربادی کی خبریں معلوم ہیں تو کیوں عبرت حاصل نہیں کرتے اور کیوں مخالفت میں بڑھتے جا رہے ہو.بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِيْ تَكْذِيْبٍۙ۰۰۲۰ حقیقت تو یہ ہے کہ کافر (شدید) انکار (کی مرض) میں (مبتلا) ہیں.تفسیر.فرماتا ہے اِن کفار کے قلب کی حالت ایسی ہو گئی ہے جو تکذیب والی ہے.کتنی ہی مثالیں اُن کے سامنے موجود ہوں یہ انکار کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں.اور جب کسی کے قلب کی حالت ایسی ہو جائے کہ وہ ہر بات کی مخالفت کرنا اپنے لئے ضروری قرار دے لے تو پھر اُسے ہدایت نصیب نہیں ہو سکتی کیونکہ ہدایت اُس وقت حاصل ہوتی ہے جب انسان غور سے کام لے اور جب اُس نے غور ہی نہ کرناہو تو ہدایت کس طرح حاصل ہو سکتی ہے.حضرت خلیفۂ اوّل رضی اللہ عنہ ہمیشہ بیان فرمایا کرتے تھے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے مخالفین کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے ایک نٹ بڑے لمبے بانس پر چڑھ جاتا اور رسّے پر چلنا شروع کر دیتا ہے.اسی طرح کبھی پتلے بانس پر پائوں رکھ کرکھڑا ہو جاتا ہے.اور جب یہ کرتب دکھا دیتا ہے تو کہتا ہے کیوں دکھایا نا کرتب.اِس پر اُنہی میں سے ایک شخص جو نیچے کھڑا ہوتا ہے سر ہلا کر کہہ دیتا ہے کہ مَیں نہ مانوں.اِس پر وہ دوسرا کرتب دکھاتا ہے اور
Page 543
پھر جب پُوچھتا ہے تو وہ یہی کہتاہے کہ مَیں نہ مانوں.تو مَیں نہ مانوں کا توکوئی علاج ہی نہیں ہوسکتا.یہی بات اللہ تعالیٰ نے اِس جگہ بیان فرمائی ہے کہ بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِيْ تَكْذِيْبٍ مخالفت میں بڑھتے بڑھتے ان لوگوں کی قلبی حالت ایسی ہو گئی ہے کہ ان کے سامنے کوئی بھی نشان ظاہر ہو.کوئی بھی معجزہ ظاہر ہو اِن کو اس بات سے کوئی غرض ہی نہیں ہوتی کہ وہ اس پر غور کریں.صرف ایک ہی مقصد اُن کے سامنے ہوتا ہے کہ ہم اِس نشان کی تکذیب کریں.پس یہ لوگ تو وہ ہیں جو تکذیب کے سمندر میں غرق ہو چکے ہیں.وَّ اللّٰهُ مِنْ وَّرَآىِٕهِمْ مُّحِيْطٌۚ۰۰۲۱ حالانکہ اللہ (اُنہیں)اُن کے پیچھے سے (آ کر)گھیرنے والا ہے.حَلّ لُغَات.مُحِیْطٌ.مُحِیْطٌ اَحَاطَ کا اسم فاعل ہے اور اَحَاطَ بِالْاَمْرِ کے معنے ہیں اَحْدَقَ بِہٖ مِنْ جَوَانِبِہٖ.کسی معاملہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا (اقرب) اور آیت مِنْ وَّرَآىِٕهِمْ مُّحِيْطٌ کے معنے ہیں لَا یَعْجِزُہُ اَحَدٌ قُدْ رَتُہٗ مُشْتَمِلَۃٌ عَلَیْھِمْ یعنی خدا تعالیٰ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا.کیونکہ اس کی قدرت و طاقت اُن پر حاوی ہے.نیز کہتے ہیں اُحِیْطَ بِہٖ اور معنے ہوتے ہیں.اُس کی ہلاکت قریب آگئی.(اقرب) پس مُحِیْطٌ کے معنے ہوں گے چاروں طرف سے گھیرنے والا.تفسیر.یہ تمسخر میں مشغول ہیں اور جب صداقت کے نشانات ظاہر کئے جاتے ہیں تو کہتے ہیں مَیں نہ مانوں.لیکن وہ اس بات سے ناواقف ہیں.کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اُن کی بداعمالیوں کے نتیجہ میں ایک خطرناک عذاب مقدّر ہے.مُـحِیْط کے لفظی معنے احاطہ کرنے والے کے ہوتے ہیں لیکن محاورہ کے رو سے اسے عذاب کے معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے.فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اُن کے پیچھے سے اُن کا احاطہ کرنے والا ہے.احاطہ کا لفظ عذابِ تام پر دلالت کرتا ہے.رستہ کُھلا ہو تو انسان بھاگ سکتا ہے لیکن جب چاروں طرف سے احاطہ ہو تو بھاگنے کے تمام راستے مسدود ہو جاتے ہیں.وَرَآئِھِمْ کے لفظ سے اس حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا کہ جب وہ عذاب آئے گا تو اُنہیں پتہ بھی نہیں لگے گا.کیونکہ پیچھے سے جو چیز آتی ہے وہ اچانک آتی ہے.پس فرمایا جب وہ عذاب اچانک طور پر آجائے گا تو چاروں طرف سے اُن کا احاطہ کر لیا جائے گا اور اُنہیں اُس عذاب سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ملے گا.حضرت مسیح موعود علیہ
Page 544
الصلوٰۃ والسلام کو بھی بار بار یہ الہام ہوا ہےکہ اِنِّی مَعَ الْاَفْوَاجِ اٰتِیْکَ بَغْتَۃً (تذکرۃ صفحہ ۲۴۲)یعنی مَیں اپنی افواج کے ساتھ اچانک آئوں گا.بَلْ هُوَ قُرْاٰنٌ مَّجِيْدٌۙ۰۰۲۲ (اس کے علاوہ) یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ وہ (کلام جو ان امور کی خبر دے رہا ہے) ایک بزرگ (ہر جگہ اور ہر زمانہ فِيْ لَوْحٍ مَّحْفُوْظٍؒ۰۰۲۳ میں) پڑھا جانے والا کلام ہے اور (مزید کمال یہ ہے کہ) وہ لوحِ محفوظ میں ہے.حَلّ لُغَات.لَوْحٌ.لَوْحٌ کے معنے ہیں کُلُّ صَحِیْفَۃٍ عَرِیْضَۃٍ خَشْبًا اَوْ عَظْمًا.لکڑی یا لوہے کی چَوڑی تختی.اور لوح کو لوح اس واسطے کہتے ہیں کہ اس پر لکھنے کی وجہ سے معانی ظاہر ہوتے ہیں(اقرب) (چونکہ لَاحَ یَلُوْحُ کے معنے جس سے لوح بنا ہے.ظاہر ہونے کے تھے اس لئے مصنّف نے وجۂ مناسبت اصل مادہ سے بیان کر دی).تفسیر.فرماتا ہے یہ لوگ تو پُرانے مکذّبین سے بھی اپنے عناد اور مخالفت میں بڑھ رہے ہیں مگر ہم کہتے ہیں یہ وہ کلام ہے جو بڑا بزرگ ہے.یہ تکذیب میں زیادتی کرنی شروع کر دیں ہم اس کی تصدیق میں زیادتی کرنی شروع کر دیں گے.گویا خدا صرف اتنی ہی غیرت نہیں دکھائے گا کہ دشمنوں کو تباہ و برباد کر دے بلکہ وہ یہ بھی کرے گا کہ اِس قرآن کو عزت کے مقام پر فائز کر دے گا اور دُنیا کی گردنیںاُس کے آگے جھکا دے گا.بیشک یہ لوگ مخالفت کریں اور جتنی چاہیں کریں مگر خدا یہ ارادہ کر چکا ہے کہ وہ اس قرآن کو عزّت کے مقام پر کھڑا کرے گا کیونکہ یہ قرآن بڑی مجد والا ہے.فِیْ لَوْحٍ مَّحْفُوْظٍ محفوظ کی قرأت ظاء کی زیر سے بھی آئی ہے اور ظ کی پیش سے بھی.یعنی مَحْفُوْظٌ بھی ہے اور مَحْفُوْظٍ بھی.زیر کی صورت میں اِس جُملہ کے یہ معنے ہوتے ہیں کہ قرآن کریم ایک محفوظ لوح میں ہے اور پیش کی صورت میں محفوظٌ قرآن کریم کی صفت بنتا ہے اور جُملہ کے معنے یہ ہوئے کہ قرآن مجید لوح میں ہے اور محفوظ ہے.ابو الفضل اور ابن خالویہ کہتے ہیں کہ لَوْحٌ لفظ نہیں بلکہ لُوْح لام کی پیش سے ہے اور اس کے معنے ساتویں
Page 545
آسمان کے اوپر کی فضا ءکے ہیں(فتح القدیر للشوکانی زیر آیت ھٰذا).یہ معنے بالبداہت باطل ہیں کیونکہ ساتویں آسمان پر گیا کون تھا کہ اُس نے وہاں کی فضاء دیکھی اور اُس کا ایک خاص نام رکھا.صحاح جوہری کہتے ہیں کہ لُوْح لام کی پیش سے ہو تو اُس کے معنے آسمان اور زمین کے درمیان کی ہوا کے ہیں(فتح القدیر للشوکانی زیر آیت ھٰذا) یعنی جَوّ اور فضاء کے یہ معنے لغت کے ہیں اور اوپر کی تفسیر کے غلط ہونے پر شاہد ہیں.ابن المنذر نے حضرت ابن عباسؓ کی طرف ایک روایت منسوب کی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ لَوْح ذکر ایک ہی لوح ہے (یعنی جس قدر ذکر خدا تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں سب اس میں درج ہیں) اور یہ لوح نور کی ہے اور تین سو سال میں ختم ہونے والے سفر کے برابر لمبی ہے.(فتح القدیر للشوکانی زیر آیت ھٰذا) ابو الشیخ کہتے ہیں کہ انسؓ سے مروی ہے کہ قرآن کریم میں جس لوح محفوظ کا ذکر ہے وہ اسرافیل کے ماتھے میں ہے (فتح القدیر للشوکانی زیر آیت ھٰذا)اور امام سیوطیؒ حضرت عباسؓ سے روایت کرتے ہیں کہ لوح محفوظ سو سال کے سفر کے برابرلمبی ہے.اللہ تعالیٰ نے قلم سے دُنیا کے پیدا کرنے سے پہلے کہا میری مخلوق کے بارہ میں میرا علم لکھ اس پر اُس نے لکھا اور جو کچھ قیامت تک ہونا تھا وہ اس میں لکھا گیا.مقاتل کہتے ہیں کہ لَوح محفوظ عرش کے دائیں طر ف رکھی ہے.(ابن کثیر سورۃ الطارق)حقیقت یہ ہے کہ یہ سب اسرائیلیات ہیں اور یہود نے بھولے بھالے مسلمانوں سے بدلہ لیا ہے.جیسا کہ حل لغات سے ظاہر ہے لوح ایک لکڑی یا ہڈی کی چوڑی سطح کو کہتے ہیں جس پر لکھا ہوا بہت واضح ہو جائے.چنانچہ اسی مادہ کا فعل لَاحَ یَلُوْحُ ہے جس کے معنے ظاہر ہونے کے ہیں.چونکہ کاغذ کا صفحہ لپیٹا جاتا ہے لیکن لکڑی لوہے یا ہڈی پر لکھی ہوئی کتاب لپیٹی نہیں جا سکتی اسے لوح کہتے ہیں اور یہ ظاہر ہے کہ جو چیز لپیٹی نہ جائے گی اس میں ایک خوبی ہو گی اور ایک نقص.خوبی تو یہ کہ ہر ایک اس کو پڑھے گا اور اس کی خوب اشاعت ہو گی اور نقص یہ کہ بوجہ کُھلی ہونے کے اس کے مٹانے یا اس میں تصرّف کرنے کا لوگوں کو زیادہ موقع مل سکے گا.اسی مضمون کو بیان کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے اس جگہ قرآن کریم کی نسبت بیان فرمایا ہے کہ وہ لوح محفوظ میں ہے یعنی قرآن کریم کی یہ خوبی ہے کہ وہ کثرت سے لوگوں کے ہاتھ میں جائے گا اور خوب پھیلے گا مگر ساتھ ہی وہ لوگوں کی دست بُرد سے محفوظ بھی رہے گا.گویا لوح پر لکھے ہوئے کلام کی خوبی تو اس کو ملے گی مگر اس کے نقص سے وہ محفوظ رہے گا.خ خ خ خ