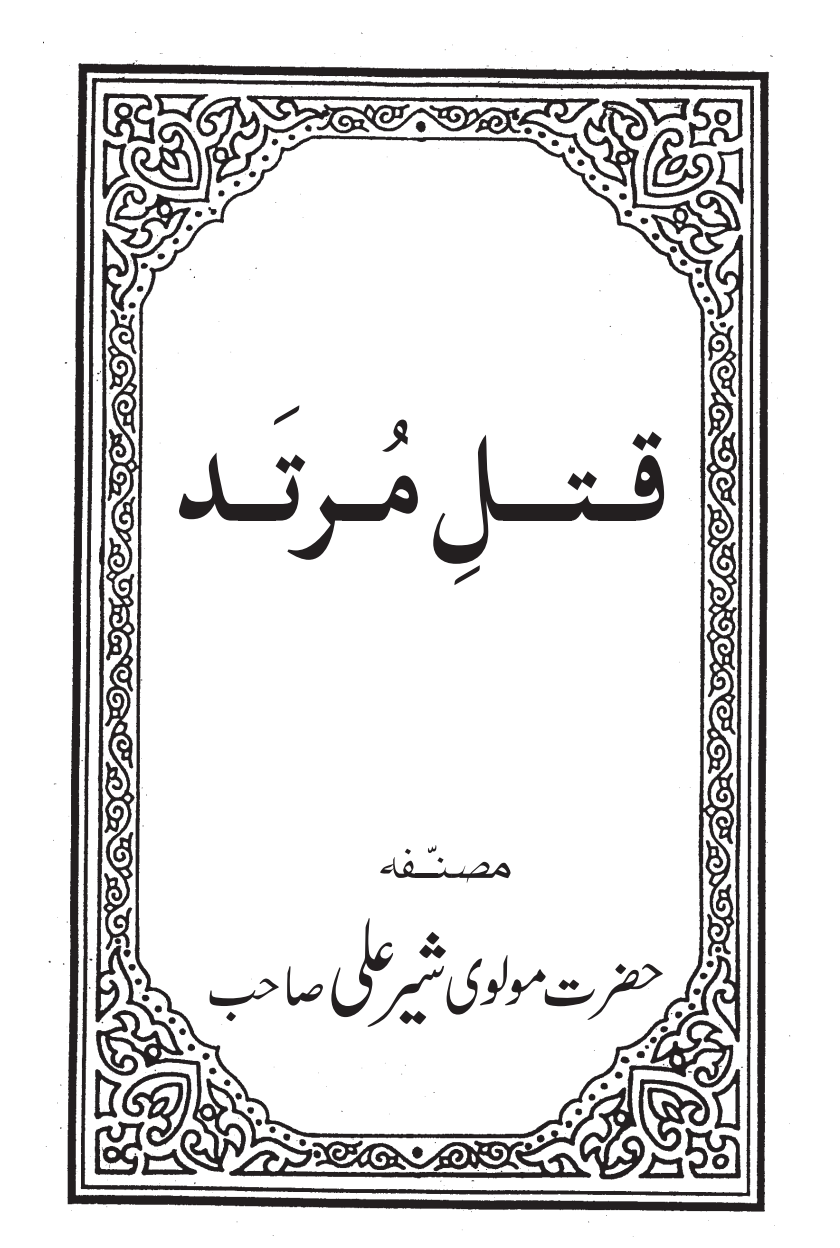Complete Text of Qatl-eMurtad Aur Islam
Content sourced fromAlislam.org
Page 1
قتلِ مُرتَد
مصنفه
حضرت مولوی شیر علی صاحب
Page 2
تصنیف
قتل مرتد اور اسلام
حضرت مولانا شیر علی صاحب
طبع اول
شائع کردہ
دسمبر 1925ء
تالیف و اشاعت قادیان
طبع دوم
نومبر 2010ء
Page 3
لأحراة والدين
قل مرند
مصفه
حضرت مولوی شیر علی صابی کے ناظر تالیف تصنیف
الحمداني
نجر
نک یو تالیف اشاعت قادیان نے
باہتمام بھائی بہادر سنگہ مینجر پر پر چھپوا کر
ماه سم برد ۲ میر تدلع کیا
بشير احمد الحملات تحرير نمو
Page 4
1
عرض حال
اس کتاب کے متعلق اس قدر بیان کر دینا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتاب
حضرت خلیفتہ اسیح الثانی امام جماعت احمدیہ کی ہدایت اور نگرانی کے ماتحت تیار کی گئی
ہے.دوسرا امر قابل ذکر یہ ہے کہ اس کتاب میں جس قدر منقولی بحث ہے اس کا اکثر
حصہ ان نوٹوں سے لیا گیا ہے جو حسب ارشاد حضرت خلیفہ امسیح الثانی، مولوی جلال
الدین صاحب شمس اور مولوی غلام احمد صاحب بد وملوی نے تیار کئے.اوّل الذکر نے
مضمون کے اس حصہ کے متعلق نوٹ مرتب کئے جن کا تعلق قرآن شریف سے ہے مگر
ساتھ ہی حدیث اور فقہ کے متعلق بھی بعض بہت مفید نوٹ تیار کئے اور مؤخر الذکر نے
زیادہ حدیث اور تاریخ کی رو سے اس مضمون کی تحقیق کی.دورانِ مضمون میں جہاں
جہاں مجھے مزید تحقیق کی ضرورت پیش آئی ہے وہاں میں نے مولوی فضل الدین
صاحب وکیل سے جو سلسلہ کے ایک محقق عالم ہیں بہت امداد حاصل کی ہے.اس مضمون
کا ایک حصہ معقولی بحث پر بھی مشتمل.ہے وہ سب کا سب اور نیز منقولی بحث کے بعض
ایسے حصے جو اصولی رنگ رکھتے ہیں حضرت مرزا بشیر احمد صاحب ایم.اے کے
افاضات کا نتیجہ ہیں کیونکہ ان حصوں کے متعلق میں نے انہی سے اشارات حاصل کئے
ہیں.پس حق یہ ہے کہ اس مسئلہ کے متعلق جس قدر تحقیق اور جو جو خیالات اس کتاب
میں پائے جاتے ہیں وہ دیگر علماء و بزرگان سلسلہ کی محنت اور دماغ کا نتیجہ ہیں.میرا
Page 5
2
کام صرف یہ ہے کہ میں نے اس تحقیق اور ان خیالات کو اپنے الفاظ میں ترتیب دے کر
ناظرین کی خدمت میں پیش کر دیا ہے.اب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس کتاب کو
مقبول فرما دے اور اس میں برکت ڈالے اور اس کے ذریعہ قتل مرتد کے غلط عقیدہ کا جو
اسلام کی طرف منسوب کیا گیا پورے طور پر قلع قمع ہو اور دنیا پر حق منکشف ہو جائے.رَبَّنَا أَرنا الحق حقا وارنا الباطل باطلاً - آمين
اللهم صل على محمد و على اله وخلفائه وبارك وسلم انك حميد مجيد.خاکسار
شیر علی عفی اللہ عنہ
قادیان دارالامان والایمان
22 /دسمبر 1925ء
Page 6
3
بسم الله الرحمن الرحيم
نحمده و نصلی علی رسوله الكريم
ھوالن خدا کے فضل اور رحم کے ساتھ
اصو
کیا اسلام میں مرتد کی سزا قتل ہے
قَدْ جَاءَكُمْ بَصَابِرُ مِنْ رَّبِّكُمْ ۚ فَمَنْ اَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ *
وَ مَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا اَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيْظِ (الانعام :105)
یقیناً تمہارے رب کی طرف سے دلائل آچکے ہیں.پس جس نے انہیں جان لیا اُس
کے اپنے فائدہ کے لئے ہوگا اور جس نے کجرا ہی اختیار کی اس کا یہ فعل اسی پر پڑے گا
اور میں تمہارا محافظ نہیں ہوں.سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہوں جس نے دنیا پر سب سے بڑا احسان
یہ کیا کہ قرآن مجید جیسی کامل کتاب بھیجی ہے جسے دوسری الہامی کتابوں پر ہزار ہا دیگر
فضیلتوں کے علاوہ ایک فضیلت یہ حاصل ہے کہ اس میں دین کو کامل کر دیا گیا ہے جیسا کہ
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :-
الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ
نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا (المائدة:4)
آج میں نے تمہارے فائدہ کے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنے احسان کو
پورا کر دیا ہے اور تمہارے لئے دین کے طور پر اسلام کو پسند کیا ہے.
Page 7
4
اس کے بعد میں اس نبی امی فداہ ابی و امی ﷺ کے حضور صلوۃ وسلام کا تحفہ
پیش کرتا ہوں جسے اللہ تعالیٰ نے رحمیہ
ہے:.للعلمین کر کے بھیجا اور جس کی نسبت اللہ تعالیٰ فرماتا
فَمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا
غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ (ال عمران:160)
اور تو اس عظیم الشان رحمت کی وجہ سے ہی جو اللہ کی طرف سے تجھے دی گئی ہے ان کے
لئے نرم واقع ہوا ہے اور اگر تو بد اخلاق اور سخت دل ہوتا تو یہ لوگ تیرے گرد سے تتر بتر
ہو جاتے.جس نے اپنے نورانی وجود میں قرآن کریم کی کامل اور پاکیزہ تعلیم کا ایک مکمل اور
مبارک نمونہ دنیا کے سامنے پیش کیا جس کی سیرت کا پورا پورا نقشہ حضرت عائشہ رضی
اللہ عنہا کے ذہن رسا نے مندرجہ ذیل مختصر الفاظ میں کھینچا ہے کہ کـان خـلـقــه
القرآن (در منثور جلد 6 صفحه 250)
قرآن شریف آپ کا خلق ہے.اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ خاتم النبین ﷺ کے اس خلیفہ
پر صلوات وسلام نازل فرمائے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قدیم وعدوں کے مطابق
چودھویں صدی کے سر پر اس لئے بھیجا کہ وہ اسلام کے چہرہ کو اس گردوغبار سے پاک
کر دے جس نے فیج اعوج کے زمانہ میں اس پر جمع ہو کر اسے دنیا کی نظر میں بدنما کر دیا تھا
اور اس کا چمکتا ہوا چہرہ اس کی صحیح اور اصلی شکل میں دنیا پر ظاہر کر دے.اما بعد ! ناظرین کرام کو علم ہے کہ گذشتہ اگست 1924ء کے آخری دن میں
ریاست کابل کی سرزمین پر ایک بہت بڑا ظلم کیا گیا.ایک نفس زکیہ کا ناحق خون کیا گیا.صرف اس لئے کہ وہ اس بات پر ایمان لایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مسیح
Page 8
5
اور مہدی کے آنے کی خوشخبری دی تھی وہ مسیح موعود اور مہدی معہود دنیا میں ظاہر ہوگیا اور خدا
کے وعدے اور مقرر کردہ نشان پورے ہوئے.اُس ہولناک واقعہ نے پرانے زمانہ کا نقشہ
ہماری نظروں میں تازہ کر دیا اور مومنین اور دشمنانِ حق کا جو تذکرہ ہم قرآن شریف میں
پڑھتے تھے اس کی تصدیق کی.کیونکہ جب ایک طرف اس شہید مرحوم نے وہی اخلاص،
وہی ایمان اور وہی ثبات دکھایا جو انبیاء کے عہد کے سچے مومن ہمیشہ دکھلاتے آئے ہیں تو
دوسری طرف کا بل کی گورنمنٹ نے اس کے ساتھ وہی سلوک کیا جو قدیم سے الہی سلسلوں
کے دشمن حق کے پرستاروں کے ساتھ کرتے چلے آئے ہیں.اگر حضرت نعمت اللہ خاں کی
مثال نے حضرت خبیب کی یاد کو ہمارے دلوں میں تازہ کیا تو کابل کے قاتلوں نے ان
عمائد قریش کا نمونہ ہمارے سامنے پیش کیا جنہوں نے بے کس اور بے بس مسلمانوں کو
نہایت بے رحمی سے شہید کیا.لیکن ہمیں کابل میں اپنے بھائیوں کے خون بہائے جانے کا
اتنا رنج نہیں جتنا اس بات کا رنج ہے کہ کابل کے قاتلوں نے اپنی اس وحشیانہ حرکت کو
اسلام کی طرف منسوب کیا ہے اور ہندوستان کے ملانوں نے ریاست کابل کے فیصلہ کی
تائید کر کے اور مولوی ظفر علی خان صاحب نے دربار کابل کی حمایت میں مضمون لکھ کر
اسلام اور پیغمبر اسلام ﷺ کی عزت اور نیک نامی پر ایک ناپاک حملہ کیا ہے اس لئے
ضرورت ہے کہ اس حملہ کا پورے طور پر جواب دیا جائے تا جو نقصان ان بزرگوں نے
اسلام کو پہنچایا ہے اس کا تدارک ہو سکے اور اسلام اور نبی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ان
نا پاک الزامات سے بریت ثابت کی جائے.سو اس غرض کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں اس
مضمون پر کچھ لکھنا چاہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ اس مضمون کے لکھنے میں
اپنی خاص تائید سے مجھ کمترین کی مدد فرمائے.رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً
مِن نِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِيةٌ (طه : 26تا29)
Page 9
6
اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور جو فرض مجھ پر ڈالا گیا
ہے اس کو پورا کرنا میرے
لئے آسان کر دے اور اگر میری زبان میں کوئی گرہ ہو تو اُسے بھی کھول دے تا کہ لوگ
میری بات آسانی سے سمجھنے لگیں.میری اس مضمون کے لکھنے سے یہ غرض نہیں کہ میں یہ ثابت کروں کہ علماء کا بل نے
احمدیوں کو مرتد قرار دینے میں غلطی کی ہے اور یہ کہ ارتداد کے لئے جو سزا بیان کی جاتی ہے
وہ احمدیوں پر چسپاں نہیں ہو سکتی کیونکہ احمدی مرتد نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کے فضل سے حقیقی اور
سچے مسلمان احمدی ہی ہیں.بلکہ اس مضمون کے لکھنے سے میری غرض یہ ہے کہ خدا تعالیٰ
کے فضل اور رحم سے دنیا پر روز روشن کی طرح یہ بات ثابت کر دوں کہ اسلام محض ارتداد کے
لئے اس دنیا میں کوئی سزا بھی تجویز نہیں کرتا بلکہ اس کے لئے صرف وہی سزا ہے جو آخرت
میں کفار کے لئے مقرر ہے.پس اصل سوال یہ نہیں کہ احمدی مسلمان ہیں اس لئے ان کو مرتد قرار دے کر قتل کرنا
ب ظلم ہے بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ مرتد کو محض ارتداد کے لئے قتل کرنا ایک ظلم ہے.اسلام
ایسی تعلیم نہیں دیتا اور یہ اسلام پر ایک بہتان ہے.احمدیوں کا سوال تو بالکل آسان ہے.ان سے جو سلوک کیا جاتا ہے وہ اس سنت اللہ
کے مطابق ہے جس کا ذکر قرآن شریف میں ہے کیونکہ قرآن شریف شہادت دیتا ہے کہ
راستبازوں کی جماعت سے ان کے دشمن ہمیشہ ایسا ہی سلوک کرتے چلے آئے ہیں اور
دشمنان سلسلہ احمدیہ نے احمدیوں کو سنگسار کر کے اور آئندہ کے لئے ان کی نسبت ایسی ہی
دھمکیوں کا اعلان کر کے بے شک اس امر کا ثبوت دے دیا ہے کہ جماعت احمد یہ ایک
راستبازوں کی جماعت ہے اور ان کے دشمن اپنے افعال اور اقوال اور رویہ سے اپنے تئیں
راستبازوں کے دشمنوں کے زمرہ میں شامل کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنے فعل سے اس
بات کا بھی ثبوت دیا ہے کہ واقعی قرآن شریف خدا تعالیٰ کا سچا کلام ہے کیونکہ اس کی باتیں
Page 10
7
ہمیشہ سچی ثابت ہوتی ہیں اور جن سنن الہیہ کا اس میں ذکر ہے وہ ہمیشہ پوری ہوتی رہتی ہیں.الغرض میر امد عا اس مضمون کے لکھنے سے صرف یہی ہے کہ میں اصولی طور پر ارتداد
کی سزا کے سوال پر بحث کروں کہ آیا یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ ایک اسلامی حکم اور شرعی حد ہے
کہ اس شخص کو جو اسلام کو ترک کرے صرف اسلام ترک کرنے کے جرم میں قتل کر دیا جائے
کہاں تک درست ہے؟ اس بارہ میں میں سب سے پہلے انشاء اللہ تعالیٰ قرآن شریف کی
تعلیم کو پیش کروں گا اس کے بعد احادیث اور اقوال فقہاء پر علی الترتیب نظر کروں گا.وماتوفيقى الا بالله العلى العظيم
Page 11
8
قرآن شریف اور قتل مرند
مسلمانوں میں سے جن علماء نے قتل مرتد کا فتویٰ دیا ہے وہ دوگروہوں میں تقسیم ہو
سکتے ہیں.ایک وہ جن کی یہ رائے ہے کہ مرتد کے قتل کی وجہ ارتداد نہیں اور اس گروہ
میں محققین مذہب حنفیہ شامل ہیں.دوسر اوہ گروہ ہے جن کا یہ خیال ہے کہ صرف ارتدار اور
تنہا ارتداد ہی وہ جرم ہے جس کے لئے بے دریغ قتل کا حکم دیا گیا ہے.چونکہ اس وقت جن
لوگوں نے اس بحث کو اٹھایا ہے اور قتل مرتد کے وجوب پر زور دیا ہے ان کا بھی یہی دعویٰ ہے
کہ اسلام محض ارتداد کے لئے قتل کی سزا مقرر کرتا ہے اس لئے میں اس گروہ کے خیالات
کی کسی قدر یہاں تشریح کرنا چاہتا ہوں.تا ناظرین کو معلوم ہو کہ یہ تعلیم جو اسلام اور نبی
اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جاتی ہے کیسی بھیا نک اور مکروہ تعلیم ہے جو ایک
دم کے لئے بھی اسلام جیسے پاکیزہ مذہب اور آنحضرت ﷺ جیسے مقدس انسان کی طرف
منسوب نہیں ہو سکتی.یہ ایسی خلاف فطرت تعلیم ہے کہ ایک معمولی درجہ کا شریف انسان بھی
اس کو کراہت کی نظر سے دیکھے گا چہ جائیکہ اشرف النبین سید الاولین والآخرین مے جسے
پاکیزہ فطرت اور مطہر انسان کو اس کا جاری کرنے والا ٹھہرایا جائے.ان لوگوں کا خیال ہے کہ چونکہ اصل وجہ قتل کی ارتداد ہی ہے اس لئے جو بھی مرتد ہو
اس کو بے دریغ تہ تیغ کر دینا چاہئیے خواہ وہ مرد ہو یا عورت.جوان ہو یا بوڑھا.آزاد ہو
یا غلام.تندرست ہو یا بیمار.غرض کوئی ہو اس کو قتل کر کے فور أواصل جہنم کرنا چاہیئے اور اس
طرح دنیا میں اسلام کی شوکت اور عظمت کا سکہ بٹھانا چاہیے.اگر ایک مرتد شیخ فانی ہے تو
اس کو اجازت نہیں دینی چاہئیے کہ وہ چند روز اور زندگی کے دن پورے کر کے اس عالم سے
Page 12
9
گزر جائے بلکہ فورا اس بوڑھے ضعیف کا سر بھی قلم کر دینا چاہئیے اور اس طرح اس کو اسلام کی
ہیبت کا مزہ چکھانا چاہئیے.اگر مرتد بیمار پڑا ہے اور اس قابل نہیں کہ بستر سے بھی اُٹھ سکے اور
بخار کی تیزی یا درد کی شدت کی وجہ سے حالت اضطراب میں ہے تو اس کو بھی مہلت نہیں دینی
چاہئیے کہ وہ شفا کا منہ دیکھے یا اس بیماری میں ہی اس عالم سے رخصت ہو بلکہ اسلامی جلا دکو
چاہئیے کہ بستر مرض پر ہی اس کے سر کو تن سے جدا کر دے تا اسلام کا جلال دنیا پر ظاہر ہو.اسی طرح اگر اسلام سے ارتداد کرنے والی ایک بڑھیا ضعیف عورت ہے اس کی
گردن بھی ہمارے علماء کے اسلام کی کھینچی ہوئی تلوار کی ضرب سے محفوظ نہیں.اسی طرح
اگر کوئی مرتد نا بینا یا پانی ہے تو وہ بھی ہمارے علماء کے ہاتھوں ذبح ہونے سے محفوظ نہیں.حالانکہ وہ قو میں جو اسلام کی بیخ کنی کے لئے مسلمانوں پر جارحانہ حملے کر رہی ہوں ان کے
بعض افراد کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امن دیا ہے اور مسلمانوں
کو حکم دیا ہے کہ ایسے
افراد کو باوجود جنگ کے قتل سے بچایا جائے لیکن ہمارے علماء کی مرتد کش تلوار سے ایسے
افراد بھی محفوظ نہیں.اسلام کی تعلیم تو یہ سکھاتی ہے کہ پیاسے کتے کو پانی پلا کر تم جنت میں جاسکتے ہو اور
ایک کا فر کو پیاس کے دکھ سے آرام دے کر خدا تعالیٰ سے اجر پاسکتے ہو.لیکن ہمارے بعض
علماء کا یہ فتویٰ ہے کہ اگر تمہارے پاس وضو کے لئے پانی ہو اور ایک مرتد پیاس سے مر رہا ہو تو
اس کو پیاس سے مرنے دو گر وضو کا پانی اسے
پھر مرتد کو اپنی جان بچانے کے لئے تو بہ کا موقع دینا بھی ایک گروہ علماء کے نزدیک
ضروری نہیں اور جائز ہے کہ بغیر ایسا موقع دینے کے مرتد کو مرد ہو یا عورت.جوان ہو یا
پیر فرتوت.تندرست ہو یا بیمار فوراً بلا تامل قتل کر دیا جائے اور جو علماء موقع دینا ضروری
سمجھتے ہیں وہ بھی اکثر تین دن سے زیادہ مہلت کی اجازت نہیں دیتے اور اس عرصہ میں بھی
علماء کا ایک گروہ ہدایت دیتا ہے کہ مرتد کو دکھ دیا جائے تا کہ وہ تو بہ کرنے پر مجبور ہو.چنانچہ
سے نہ دو.
Page 13
10
مولوی ظفر علی خاں صاحب اس کی تائید میں فقہ حنبلی کی مشہور کتاب المقنع سے
ذیل عبارت نقل کرتے ہیں:.فمن ارتد عن الاسلام من الرّجال والنساء و هو بالغ عاقل دعى
اليه ثلاثة ايام وضيق عليه فان لم يتب قتل.لا يجب استتابته بل
تستحب و يجوز قتله في الحال.،،
جو شخص اسلام سے مرتد ہو جائے خواہ وہ مرد ہو یا عورت اور عاقل و بالغ ہو تو اسے تین
روز تک اسلام کی طرف بلایا جاوے اور اسے تنگ کیا جائے اگر توبہ نہ کرے تو قتل کیا
جائے.تو بہ طلب کرنا واجب نہیں بلکہ مستحب ہے اور مرتد کو معا قتل کر ڈالنا بھی جائز
ہے.ایسا ہی لکھا ہے کہ اگر مرتد کوکوئی شخص بغیر قاضی یا بادشاہ کے حکم کے جان بوجھ کر یا
بھول کر قتل کر دے یا اس کی آنکھ پھوڑ دے یا ناک کاٹ دے یا ٹانگ تو ڑ دے،غرض کچھ
کرے اس سے کوئی باز پرس نہیں.یہ اس
تعلیم کا مختصر خاکہ ہے جو آج مولوی صاحبان اسلام کے نام سے دنیا کے
آگے پیش کر رہے ہیں.ایک نے ان میں سے جن کا نام نامی ” شبیر احمد عثمانی“ ہے یہاں
تک جسارت کی ہے کہ کہہ دیا ہے کہ یہ تعلیم صریح طور پر قرآن شریف میں موجود ہے مگر
دوسروں نے ایسی جرات نہیں کی بلکہ یہ کہا ہے کہ قرآن شریف اس امر کے متعلق ساکت
ہے.چنانچہ مولوی ظفر علی خاں صاحب اپنے مضمون میں لکھتے ہیں:.بلا شبہ یہ صحیح ہے کہ ہمدرد کی پیش کردہ آیات میں مرتد کے لئے سزائے قتل کا ذکر
نہیں اور ذاتی طور پر میرا خیال ہے کہ غالباً کسی دوسری آیت میں بھی بالتصریح ایسا حکم نظر
نہیں آتا.“
مولوی ظفر علی خاں صاحب نے تو ”بالتصریح ذکر نہ ہونے کی شرط بڑھا کر
Page 14
11
مولوی شبیر احمد صاحب کی خاطر داری کو ایک حد تک ملحوظ رکھا مگر مولوی شاکر حسین صاحب
سہسوانی نے 23 / مارچ کے زمیندار میں صاف لکھ دیا کہ
اس امر میں اختلاف کی کوئی وجہ نہیں کہ قرآن پاک میں قتل مرتدین کا کوئی
صریح و غیر صریح حکم موجود نہیں ہے.“
مگر ساتھ ہی مولوی سہسوانی صاحب اور مولوی ظفر علی خاں صاحب فرماتے ہیں
که سارا دین محض قرآن میں محدود نہیں.زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ قرآن نے
مرتد کی دنیوی سزا کے متعلق سکوت اختیار کیا ہے لیکن قرآن حکیم بعض دیگر احکام مثلاً حدّ
شارب وغیرہ کے متعلق بھی اسی طرح ساکت ہے.لہذا اصولاً کہا جائے گا کہ قرآن کریم
اس بارے میں ایسا ہی ساکت ہے جیسا کہ بعض دیگر احکام شرعی ہیں.اس کے جواب میں ہم اس بات کے مدعی ہیں کہ شریعت کے تمام تفصیلی احکام
قرآن شریف میں موجود ہیں اور بے شک یہ درست ہے کہ بعض تفاصیل قرآن شریف
میں نہیں پائی جاتیں.مگر ان تمام تفاصیل کی جڑ اور ان کا اصل قرآن شریف میں موجود
ہے.قرآن شریف ایک کامل کتاب ہے اور جتنے احکام آنحضرت عمﷺ نے اپنی امت
کے لئے جاری فرمائے وہ یا تو بالصراحت قرآن شریف میں مذکور ہیں یا ان کا پیج کلام
ربانی میں پایا جاتا ہے.اس لئے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر بالصراحت قتل مرتد کا حکم قرآن
شریف میں نہیں پایا جاتا تو کیا بطور پیج اور تم کے اس حکم کا کوئی نشان قرآن میں ملتا ہے؟ یہ تو
ہو سکتا ہے کہ ایک تفصیلی حکم قرآن شریف میں نہ پایا جاتا ہو مگر یہ نہیں ہوسکتا کہ
آنحضرت نے کوئی ایسا حکم نافذ فرمایا ہو کہ جو نہ صرف اس کا اصل ہی قرآن شریف
میں موجود نہ ہو بلکہ وہ قرآن شریف کی عام تعلیم اور اس کی روح اور سپرٹ کے بھی خلاف
ہو.محتل مرتد کا مسئلہ یعنی یہ مسئلہ کہ اگر کوئی شخص اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور مذہب اختیار
Page 15
12
کرے تو اسے بلا تامل اور بلا دریغ صرف ارتداد اور محض ارتداد کی سزا میں
قتل کر دیا جائے.یہ بھی ایسا مسئلہ ہے کہ قرآن شریف میں اس کا بیج ہی مفقود نہیں بلکہ یہ مسئلہ قرآن شریف کی
تمام تعلیم کے خلاف اور اس کے بالکل الٹ ہے اور اس مسئلہ کو قرآن شریف سے وہی
نسبت ہے جو تاریکی کو نور سے ہے اور جس طرح نو راور ظلمت ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے ایسا
ہی قرآن شریف کی تعلیم قتل مرتد کے مسئلہ کے ساتھ جمع نہیں ہوسکتی.قرآن شریف کی تعلیم
قتل مرتد سے ایسی ہی دور ہے جیسے مغرب سے مشرق بلکہ اس سے بھی زیادہ اور ان میں
باہمی وہی تفاوت ہے جو بیچ اور جھوٹ میں تفاوت ہے.اگر یہ مسئلہ درست ہے تو پھر نعوذ
باللہ قرآن شریف جھوٹا ہے اور اگر قرآن شریف سچا ہے تو پھر ہمیں ماننا پڑے گا کہ یہ مسئلہ
جس رنگ میں آج ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے بالکل غلط ہے یعنی یہ کہ ایک مرتد کو محض
ارتداد اور تنہا ارتداد کے جرم میں قتل کر دینا واجب یا جائز ہے.ہے.ناظرین ملاحظہ فرما چکے ہیں کہ قتل مرتد کے متعلق ان لوگوں کے کیا کیا خیالات ہیں
جن کا یہ دعویٰ ہے کہ ہر ایک مرتد صرف ارتداد اور محض ارتداد کے لئے واجب القتل
اب ہم قرآن شریف کی طرف رجوع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ایسے خیالات کا کچھ
اصل قرآن شریف میں بھی پایا جاتا ہے اور کیا یہ مسئلہ قرآن شریف کی تعلیم سے ذرہ بھی
مناسبت رکھتا ہے یا بالکل اس کے الٹ اور مخالف ہے؟
اسلام ایک علمی مذہب ہے
جب ہم قرآن شریف پر نظر کرتے ہیں تو سب سے پہلی بات جو ہماری آنکھوں
کے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن شریف اسلام کو ایک سائنس اور فلسفہ کے رنگ میں
پیش کرتا ہے.سب سے پہلی وحی ہی کو دیکھو جو آنحضرت ﷺ پر غار حرا میں نازل
ہوئی.قرآن شریف کی ان پانچوں آیتوں کو پڑھو جو سب سے اوّل بطور پیش خیمہ آسمان
Page 16
13
سے اُتریں.یہ پانچ آیتیں پانچ پھول ہیں جو اسلامی بہار کے آغاز میں کھلے.ان کو
سونگھو اور دیکھو کہ ان سے کیسی خوشبو آتی ہے تا آپ کو معلوم ہو کہ اس موسم بہار میں کس
رنگ کے پھول کھلنے والے تھے.یہ پانچ آیتیں اسلام کے باغ کا سب سے پہلا پھل
ہیں ان کو چکھو اور ان سے اندازہ لگاؤ کہ اس باغ کے دوسرے پھل کس رنگ اور کس مزہ
کے ہونے چاہئیں.وہ پانچ آیتیں، وہ اسلام کا پہلا پیغام جواہل دنیا کے نام آسمان سے
نازل ہوا یہ ہے.اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ & اِقْرَأْ وَرَبُّكَ
الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ ﴾ (العلق : 62)
ان آیات سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ کیا یہی نہیں کہ اب ایک ایسا دین اتر نا شروع ہوا
ہے کہ جو ایک علم کے رنگ میں دنیا کے سامنے پیش کیا جائے گا اور اس کی اشاعت قلم کے
ذریعہ یعنی دلائل اور براہین کے ذریعہ ہوگی نہ جبر وا کراہ کے ذریعہ.قرآن شریف کے سوا
اور کونسی کتاب ہے جس کے جھنڈے پر قلم کا نشان ہے؟ اور اسلام کے سوا اور کونسا دین ہے
جس نے علم کو اپنا Motto اور مقصود قرار دیا ہے.تمام دنیا کے مذاہب میں سے یہ امتیازی
نشان صرف اسلام نے اپنے لئے انتخاب کیا ہے.پس کیا یہ ظلم نہیں کہ ایسے دین کی نسبت
جو قلم کے ساتھ دنیا پر ظاہر ہوا اور جس نے اپنے پیغام
کو علم کے لفظ سے تعبیر کیا یہ کہا جائے کہ
اس نے اپنی اشاعت کے لئے اپنے پیروؤں کو حکم دیا کہ وہ تلوار کے زور سے لوگوں کو اپنے
دین میں داخل کریں اور جو داخل ہو کر نکلنا چاہے اس کا سر قلم کر دیں.اپنی تلوار کی دھار پر گھمنڈ کر نیوالو! ممکن ہے کہ قلم اور دوات تمہاری نظر میں بہت
حقیر اور ذلیل ہوں مگر خدا ان کو عزت دیتا ہے اور ان کے نام پر اپنی پاک کتاب میں قسم
کھاتا ہے.قرآن شریف میں اس سورۃ شریفہ کو تلاش کرو جس کا نام سورۃ القلم رکھا گیا ہے
اور دیکھو وہ کن مبارک الفاظ کے ساتھ شروع ہوتی ہے.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:.
Page 17
14
ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ (القلم: 2)
ہم قلم اور دوات کو اور اس کو جو ان کے ذریعہ سے لکھا جاتا ہے شہادت کے طور پر پیش
کرتے ہیں.پس جس کو تم حقیر سمجھتے ہو خدا تعالیٰ اس کو عزت دیتا ہے اور اس کے نام پر قسم کھاتا
ہے.اگر اسلام ایک جنگی مذہب تھا تو چاہیے تھا کہ سیف و سنان
کی قسم کھاتا نہ کہ
ن و القلم وما يسطرون کی.کیا تمہیں کہیں نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تلوار اور نیزے
اور بندوق کی بھی قسم کھائی ہے؟ قلم تو یہ فخر کر سکتا ہے کہ قرآن شریف کی ایک سورۃ کریمہ
اس کے نام سے موسوم ہے
مگر کیا تلوار یا نیزہ کو بھی عزت دی گئی ہے؟
پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تمام قرآن مجید اس پہلی وحی الہی کے رنگ میں رنگین ہے جو قلم
کے نشان کے ساتھ علم کا جھنڈا ہاتھ میں لئے ہوئے دنیا پر نازل ہوئی کیونکہ ہم دیکھتے
ہیں کہ اس نے اپنی ہر ایک بات کو علم کے پیرا یہ میں دنیا کے سامنے پیش کیا ہے.وہ صرف
یہی نہیں کہتی کہ ایک خدا پر ایمان لاؤ بلکہ خدا کی ہستی کے زبر دست دلائل بھی ساتھ ہی پیش
کرتی ہے.وہ صرف ہمیں یہ نہیں بتاتی کہ خدا کی ذات فلاں فلاں صفات سے متصف
ہے بلکہ ان صفات کے مظاہر بھی ہمارے سامنے رکھ دیتی ہے تا ہمیں ان صفات کے متعلق
یقین حاصل ہو.وہ صرف یہی نہیں کہتی کہ الہام اور وحی کا نزول دنیا کی ہدایت کے لئے
ضروری ہے بلکہ بدلائل اس دعوی کو ثابت کرتی ہے.وہ صرف اتنا ہی نہیں کہتی کہ خدا کے
رسولوں اور نبیوں پر ایمان لاؤ بلکہ وہ ہمیں وہ معیار بھی بتلاتی ہے جن کے ذریعہ ہم سچے اور
جھوٹے مدعیوں میں امتیاز کر سکیں.وہ صرف ہمیں یہی نہیں سکھاتی کہ اس زندگی کے بعد
ایک اور زندگی ہے جو جزاوسزا کی زندگی ہے بلکہ وہ اس کا ثبوت بھی پیش کرتی ہے.غرض
جوامور ایمانیات کے متعلق ہیں وہ ان کے متعلق ہم سے اس امر کا مطالبہ نہیں کرتی کہ ہم
ان کو اندھا دھند مان لیں بلکہ پہلے دلائل کے ساتھ ان کی حقیقت کا یقین ہمارے دلوں
Page 18
15
پر بٹھاتی ہے اس کے بعد ان پر ایمان لانے کا حکم دیتی ہے.قرآن شریف ہمیں صرف یہی حکم نہیں دیتا کہ نماز پڑھو، روزے رکھو ، زکوۃ ادا
کرو، صدقہ دو، حج کرو، فلاں بدی سے بچو اور فلاں نیکی اختیار کرو بلکہ ان احکام کی حکمت
اور ان کے فوائد بھی ساتھ ہی بیان فرماتا ہے.تاہم شوق سے بطیب خاطر ان اعمال کو
بجالائیں اور ان کو ایک بوجھ نہ سمجھیں.ہم قرآن شریف میں جا بجاد یکھتے ہیں کبھی وہ ہماری توجہ صحیفہ قدرت کی طرف
پھیرتا ہے اور کبھی وہ ہماری عقل سلیم اور فطرت کے آگے اپیل کرتا ہے اور ہمیں غور اور فکر
اور تدبر سے کام لینے کی ترغیب دیتا ہے.کبھی وہ سفن الہیہ اور اللہ تعالیٰ کے غیر مبدل
قوانین کا ذکر کرتے ہوئے گذشتہ واقعات اور پہلے انبیاء اور ان کی قوموں کی مثال سے
عبرت حاصل کرنے کی تحریک کرتا ہے.کبھی وہ نہایت ہی پیچیدہ اور مغلق مسائل کو نہایت
ہی آسان پیرا یہ میں حل کر کے دکھاتا ہے اور کبھی وہ مخالفین کے اعتراضات کا رد کر کے ان
پر اتمام حجت کرتا ہے.کبھی وہ عقائد باطلہ اور خصائل رذیلہ کو عقائد حقہ اور اخلاق فاضلہ
کے مقابل میں رکھ کر اسلامی تعلیمات کی فضیلت کو طالبان حق پر واضح کرتا ہے اور کبھی
ہماری ضمیر اور کانشنس سے اپیل کر کے ہماری زبان سے حق کا اقرار کرواتا ہے.غرض کوئی
علمی، ذہنی، عقلی اور فطری ذریعہ نہیں جس کو وہ کام میں نہیں لاتا اور کوئی سمجھانے کا طریق
نہیں جس کو وہ استعمال نہیں کرتا.ہر ایک شخص جو قرآن شریف کا کچھ بھی علم رکھتا ہے اس امر کی شہادت دے گا کہ
لوگوں کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لئے قرآن شریف اس بات کی جابجا ترغیب دیتا
ہے کہ وہ غور اور تدبر سے کام لیں.کبھی تو وہ فرماتا ہے :.إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ
لَايَتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيمًا وَقُعُودًا و
Page 19
16
عَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ (ال عمران:191 192)
آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے آگے پیچھے آنے میں عقلمندوں
کے لئے یقیناً کئی نشان موجود ہیں.وہ عقلمند جو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر اللہ کو
یاد کرتے رہتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش کے بارے میں غور وفکر سے کام
لیتے ہیں.کبھی وہ فرماتا ہے:.أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوْبِ أَقْفَالُهَا (محمد: 25)
کیا وہ قرآن پر غور نہیں کرتے کیا ان کے دلوں پر قفل لگے ہوئے ہیں.کبھی فرماتا ہے:.أنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ (الانعام: 66)
دیکھ ہم دلیلوں کو کس طرح بار بار بیان کرتے ہیں تا کہ وہ سمجھیں.غرض قرآن شریف بار باراَ فَلَا تَعْقِلُونَ اور اَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ.لَعَلَّكُمْ
تَتَفَكَّرُونَ.اَفَلَا يَعْقِلُونَ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ.اور ایسے ہی الفاظ کہ کر انسان کی عقل سے
اپیل کرتا ہے اور اس کو غور اور فکر کی تحریک کرتا ہے اور منافقوں اور کفار کی نسبت فرماتا ہے:.صمٌّ بُكْمُ عَلَى فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ) (البقرة:172) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا
لَا
يَعْقِلُونَ (المائدة: 59) الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ (الانفال: 23)
لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ
أَذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَيكَ كَالْاَ نْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَيكَ هُمُ
الْغُفِلُونَ (الاعراف: 180)
یہ لوگ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں اس لئے سمجھتے نہیں.یہ اس لئے ہے کہ وہ ایسے
لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے.یہ بہرے اور گونگے ہیں جو کچھ بھی عقل
Page 20
17
نہیں رکھتے.ان کے دل تو ہیں مگر ان کے ذریعہ سے وہ سمجھتے نہیں اور ان کی آنکھیں تو
ہیں مگر ان کے ذریعہ سے وہ دیکھتے نہیں اور ان کے کان تو ہیں مگر ان کے ذریعہ سے وہ
سنتے نہیں.یہ لوگ چار پایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر.اصل بات یہ ہے کہ یہ
بالکل جاہل ہیں.پس قرآن شریف شروع سے لے کر آخر تک انسان کو اپنی عقل اور دانش اور
آنکھوں اور کانوں اور غور وفکر سے کام لینے کی ترغیب دیتا ہے اور ہر ایک بات دلیل کے
ساتھ منواتا اور ہر ایک حکم کی حکمت بیان فرماتا ہے.پھر یہی نہیں کہ قرآن شریف خود دلائل
سے اپنے دعوی کی سچائی ثابت کرتا ہے بلکہ حق کے مخالفوں سے بھی دلائل کا مطالبہ کرتا
ہے.چنانچہ فرماتا ہے:.قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَدِقِينَ (البقرة: 112)
(اے پیغمبر ) تو انہیں کہہ دے کہ اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل پیش کرو.پھر فرماتا ہے:.وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلُ بِهِ سُلْطَنَا وَ مَا
لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ (الحج: 72)
اور وہ لوگ اللہ کے سوا ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جن کے لئے اس نے کوئی دلیل
نہیں اُتاری اور جن کے متعلق ان
کو کسی قسم کا کوئی علم حاصل نہیں.پس کیا یہ ظلم نہیں کہ ایسے دین کی نسبت جس کا دارو مدار دلائل اور براہین پر ہے اور
جو عین فطرت صحیحہ کا نقشہ ہے اس کی نسبت یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اُن تمام لوگوں کے سروں پر
جو اس کو قبول کریں ایک شمشیر برہنہ آویزاں رکھتا ہے اور ہر آن ان کو اس کی طرف سے یہ
دھمکی مل رہی ہے کہ اگر تم مجھے ترک کرنے کا خیال بھی کرو گے تو یاد رکھو یہی شمشیر تمہارے
سر پر گرے گی اور تمہیں ہلاک کر دے گی.
Page 21
18
طریق تبلیغ
پھر اس طریق کو دیکھو جو اسلام کی تبلیغ کے لئے قرآن شریف سکھاتا ہے.جب ہم
قرآن شریف پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں صاف معلوم ہوتا ہے کہ جیسا خود وہ اپنے اصول اور
احکام کی خوبی اور کمال کو ظاہر کرنے کے لئے حکیمانہ طریق اختیار کرتا ہے اور دلائل قویہ اور
بج نیرہ کے ذریعہ اپنی تعلیم کی خوبی لوگوں کے ذہن نشین کرتا ہے ایسا ہی مبلغین اسلام کو بھی
یہی ہدایت دیتا ہے کہ وہ نہایت ہی احسن طریق سے لوگوں کو اسلام کی طرف بلائیں.وہ
اپنے پیروؤں کو یہ نہیں سکھا تا کہ تم جابرانہ اور قاہرانہ طریق سے اسلام کی اشاعت کرو بلکہ
وہ یہ کہتا ہے کہ حکمت اور موعظہ حسنہ کے ذریعہ تم لوگوں کو اسلام کی طرف بلاؤ.چنانچہ سورۃ
النحل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:.اُدْعُ إِلَى سَبِيْلِ رَبَّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ (النحل: 126)
لوگوں کو حکیمانہ طریق سے اور اچھی اچھی نصیحتوں سے اپنے پروردگار کے رستہ کی طرف
بلاؤ اور ان کے ساتھ بحث ایسے طور پر کرو کہ وہ لوگوں کے نزدیک بہت ہی پسندیدہ
ہو.پھر اللہ تعالیٰ اہل کتاب کا ذکر کر کے فرماتا ہے:.وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتُبِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ (العنكبوت: 47)
اہل کتاب کے ساتھ جھگڑا نہ کیا کرو مگر ایسے طریق سے جو نہایت ہی احسن ہو.مندرجہ بالا آیات سے صاف ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ مسلمان جب
اپنے دین کی تبلیغ کریں تو نہایت ہی احسن طریق اختیار کریں اور نہایت ہی نرمی اور رافت
اور ہمدردی کے ساتھ لوگوں کو اسلام کی طرف بلائیں.اب بتلاؤ کسی کو یہ کہنا کہ تم اسلام
میں داخل ہو جاؤ ورنہ زیادہ سے زیادہ تم کو تین دن کی مہلت دی جاتی ہے اگر اس عرصہ کے
Page 22
19
اندر تم واپس اسلام میں داخل نہ ہو گئے تو تمہیں قتل کیا جائے گا.کیا یہی طریق ہے جو قرآن
شریف کی آیات سے مستنبط ہوتا ہے؟
ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے
قرآن شریف کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی کو حق کے قبول کرنے کی توفیق
دینا اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے.کوئی شخص خواہ کتنا ہی کسی کو راہ راست پر لانے کی کوشش
کرے جب تک اللہ تعالیٰ کسی کے سینہ کو اسلام کے قبول کرنے کے لئے نہ کھول دے وہ
اسے قبول نہیں کر سکتا.چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:.فَمَنْ يُرِدِ اللهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ (الانعام: 126)
جس شخص کے متعلق خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ اسے راہِ راست دکھائے اس کے سینہ کو قبول
اسلام کے لئے کھول دیتا ہے.پھر فرماتا ہے:.إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ اَحْبَبْتَ وَلكِنَّ اللَّهَ يَهْدِى مَنْ يَشَاءُ
وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (القصص:57)
اپنی خواہش کے مطابق تم جس کو چاہو ہدایت نہیں دے سکتے بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے
ہدایت دیتا ہے اور وہی راہ پر آنے والوں کے حال سے خوب واقف ہے.غرض قرآن شریف کی مندرجہ بالا اور اسی مضمون کی اور بہت سی آیات سے ثابت ہوتا
ہے کہ ہدایت ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے اور جس کو اللہ تعالیٰ
اس
کی توفیق دینا چاہتا ہے اس کے سینہ کو کھول دیتا ہے.پس ثابت ہوا کہ کسی کو اسلام
میں داخل کرنا ہمارے اختیار میں نہیں.یہ دل کا فعل ہے اور کسی تلوار کی دھار اس دل تک
نہیں پہنچ سکتی جس کے ساتھ اسلام لانے یا نہ لانے کا تعلق ہے.وہ دل انسانی زد سے
Page 23
20
بہت دور ہے نہ وہاں انسانی تلوار کام کر سکتی ہے اور نہ بندوق.کوئی ہاتھ نہیں جو اس دل کو
پھیر سکے اور کوئی ہتھیار نہیں جو اس پر اثر کر سکے.ہاں
تم یہ کہہ سکتے ہو کہ اگر چہ ہدایت ہمارے اختیار میں نہیں لیکن ہمارا یہ فرض
ہے کہ ہم اسباب سے کام لیں.نتائج کا مرتب کرنا بے شک خدا تعالیٰ کے اختیار میں
ہے.لیکن اس کے یہ معنے نہیں کہ ہم تدبیر اور سعی کے فرض سے سبکدوش ہو گئے.ہاں
بے شک تم نے سچ کہا مجھے اس امر سے پورا اتفاق ہے اگر چہ ہدایت پانے کی توفیق
دینا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے مگر ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم لوگوں کو راہ راست پر لانے
کی کوشش کریں.مگر مجھے بتاؤ وہ کون سے ذرائع ہیں جو کسی کو حق کی طرف راہنمائی
کرنے کے لئے استعمال کئے جا سکتے ہیں؟ وہ کونسی نشتر ہے جو آنکھوں کے پردوں کو
چی سکتی ہے؟ وہ کس توپ کی گرج ہے جو کانوں کی گرانی کو دور کر سکتی ہے؟ وہ کونسی تلوار
ہے جو دل کی بند کھڑکی کو کھول سکتی ہے؟ کیا وہی تلوار جس کی نسبت مولوی شبیر حسین
صاحب دیو بندی فرماتے ہیں کہ اخر الحيل السيف اور جس کی نسبت مولوی
ظفر علی صاحب لکھتے ہیں کہ قرآن میں اس کو تلاش کرنا فضول ہے.اس کو ڈھونڈ نا ہوتو
کابل کے اسلحہ خانہ میں تلاش کرو.اے اسلام کو بدنام کرنے والے مولویو! بتاؤ کیا
یہی تلوار دلوں کے بند قلعوں کو فتح کر سکتی ہے؟ کیا دلوں کے قفل کھولنے والی یہی چابی
ہے جو تمہارے ہاتھ میں دی گئی؟ کیا تسخیر قلوب کے لئے یہی خاص تدبیر ہے جس پر تم
کو ناز ہے؟ افسوس ! صد افسوس!!
آؤ میں تمہیں بتاؤں وہ تلوار جس کی چوٹ دل پر لگتی ہے وہ لو ہے یا فولاد کی تلوار
نہیں بلکہ وہ دلائل قاطعہ اور براہین ساطعہ کی تلوار ہے.وہ نیزہ جو انسان کے سینہ کو چیرتا
ہے وہ لکڑی اور لوہے کا نیزہ نہیں بلکہ وہ وہ نیزہ ہے جس کے چلانے کے لئے قرآن شریف
کی اس آیت میں حکم دیا گیا ہے:.
Page 24
21
وَقُل لَّهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيْفًا (النساء:64)
ان سے ایسی باتیں کرو جو اچھی طرح ان کے دلوں پر اثر کریں وہ حربہ جس کے
چلانے کے لئے اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتا ہے خود اسلام کی تعلیم ہے جس کی نسبت اللہ تعالیٰ
فرماتا ہے:.فِطْرَتَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا (الرّوم: 31)
یعنی یہ دین کیا ہے؟ خدا کی بنائی ہوئی سرشت ہے جس خدا نے لوگوں کو پیدا کیا ہے.لوہا
لوہے کو کا تھا ہے اور فطرت انسانی پر وہی چیز اثر کر سکتی ہے جو عین فطرت کے مطابق ہو.پس دشمن کے دل کو فتح کرنے کے لئے سب سے بڑا ہتھیار خود قرآن شریف ہے.اس
نے وہ کام کیا جو کوئی تلوار نہیں کر سکتی.وہی ہتھیار اب بھی موجود ہے مگر ہمارے مخالف
مولوی صاحبان کے ہاتھ میں طاقت نہیں کہ اس کو چلا سکیں اس لئے اس آسمانی تلوار کو چھوڑ
کر زمینی تلوار کی طرف جھک گئے ہیں.خلاصہ کلام یہ ہے کہ کسی کو ہدایت دینا ہمارے اختیار میں نہیں اس لئے تلوار کے
ذریعہ کسی کو اسلام کی طرف لوٹانے کی کوشش کرنا ایک بے سود فعل ہے.ہمارا کام صرف پہنچا دینا ہے
اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں بار بار ہمیں سمجھاتا ہے کہ ہمارا کام صرف پیغام پہنچانا
ہے کسی کو اسلام لانے کے لئے مجبور کرنا ہمارا کام نہیں.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:.مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَاغُ (المائدة: 100)
کہ رسول پر صرف بات کا پہنچانا واجب ہے.پھر فرماتا ہے:.ج
وَاطِيعُوا اللهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ
Page 25
22
فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلْغُ الْمُبِينُ (المائدة:93)
اور تم اللہ کی بھی اطاعت کرو اور اس رسول کی بھی اطاعت کرو اور ہوشیار رہو اور اگر تم پھر
گئے تو جان لو کہ ہمارے رسول کے ذمہ تو کھول کھول کر پہنچا دینا ہی ہے.پھر فرماتا ہے:.وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ وَالْأُمِّينَ وَ أَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ
اهْتَدَوا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْخُ وَاللهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ (ال عمران: 21)
(اے پیغمبر) اور ان لوگوں کو جنہیں کتاب دی گئی ہے کہہ دے نیز امیوں کو بھی کہ کیا تم
فرمانبردار ہوتے ہو.پس اگر وہ فرمانبردار ہو جائیں تو سمجھو کہ وہ ہدایت پاگئے اور اگر وہ
منہ پھیر لیں تو تیرے ذمہ صرف پہنچادینا ہے اور اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے.مندرجہ بالا آیات اور اسی مضمون کی بہت سی دیگر آیات سے یہ امر روز روشن کی
طرح عیاں ہے کہ رسول کا کام صرف یہی ہے کہ وہ خدا کے پیغام کو لوگوں تک پہنچا دے
اس کا یہ کام نہیں کہ وہ لوگوں کو اس کا پیغام قبول کرنے کے لئے مجبور کرے اور رسول کی
امت اپنے نبی کے تابع ہوتی ہے.پس اگر مجبور کرنا نبی کا کام نہیں تو اس کے اتباع کا کس
طرح ہو سکتا ہے؟
یہ بھی یادر ہے کہ اس مضمون کی آیات صرف ملتی ہی نہیں بلکہ ان میں مدنی آیات
بھی شامل ہیں.پس جس طرح مکہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف حکم الہی کا
پہنچا دینا تھا ایسا ہی مدینہ میں بھی اتنا ہی کام تھا اور زور کے ساتھ کسی کو داخل کرنا یا داخل
ہونے کے بعد اس کو اسی دین میں رہنے پر مجبور کرنا آپ کا کبھی کام نہیں ہوا اور نہ اس کی
کوئی مثال آپ کے متعلق ملتی ہے.لیکن آج مسلمان کہلانے والے اسلام کے سب سے
بڑے خیر خواہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے لوگوں کو جبر مسلمان رکھنے اور بے دریغ قتل کر دینے
کا حکم دیا ہے.بہیں تفاوت راہ از کجاست تا یکجا.
Page 26
23
دوسروں کی گمراہی کے ہم جواب دہ نہیں
قرآن شریف سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنا فرض تبلیغ ادا کر چکیں اور پھر بھی کوئی
نہ مانے تو ہم بری الذمہ ہیں، ہم ایسے لوگوں کی گمراہی کے ذمہ دار نہیں.اللہ تعالیٰ سورۃ
مائدۃ میں فرماتا ہے:.يَايُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَّنْ ضَلَّ
إذَا اهْتَدَيْتُمْ (المائدة: 106)
مسلمانو! تم اپنی خبر رکھو.جب تم راہ راست پر ہو تو کوئی بھی گمراہ ہو ا کرے اس کا گمراہ
ہونا تم کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا.اسی طرح فرماتا ہے :.مَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا
وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى (بنی اسراء يل: 16)
جو شخص سیدھے رستہ پر چلا تو اپنے ہی فائدہ کے لئے سیدھے رستہ پر چلتا ہے اور جو بھٹکا
تو اس کے بھٹکنے کا خمیازہ بھی اسی کو بھگتنا پڑے گا اور کوئی متنفس کسی دوسرے تنفس کے
بارکو اپنے اوپر نہیں اٹھاتا.جب ہم سے گمراہ ہونے والوں کے متعلق کوئی باز پرس نہیں ہوگی بشرطیکہ ہم امر
بالمعروف پر عمل کرتے رہیں تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو مجبور کریں کہ وہ
بہر حال ہماری رائے کے ساتھ اتفاق کریں اور انکار کی صورت میں ہم ان کو قتل کر دیں.قرآن شریف حکم دیتا ہے کہ نہ ماننے والوں سے اعراض کرو
مخالف کہتا ہے کہ اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ نہ ماننے والوں کو قتل کرو مگر قرآن شریف
Page 27
24
کہتا ہے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو.چند آیات صرف بطور نمونہ پیش کرتا ہوں.اللہ تعالیٰ
فرماتا ہے:.فَاعْرِضْ عَنْ مِّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَوةَ الدُّنْيَا (النجم:30)
اور جو شخص ہمارے ذکر سے منہ پھیر لیتا ہے اور سوائے دنیا کی زندگی کے اور کچھ نہیں
چاہتا ، تو بھی اس کی طرف سے منہ پھیر لے اور اس کی پیروی نہ کر.پھر فرماتا ہے:.فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنتَ بِمَلُوْمٍ وَذَكِرْ فَإِنَّ الذِّكْرُى
تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ (الذاريات: 55، 56 )
پس اے نبی تو ان سے منہ پھیر لے اور تجھ کو ان کے کاموں کی وجہ سے کوئی ملامت نہیں
کی جائے گی اور یاد دلا تارہ کیونکہ یاددلا نا مومنوں کو نفع بخشا کرتا ہے.پھر فرماتا ہے:.وَاعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ وَلَوْ شَاءَ اللهُ مَا أَشْرَكُوا (الانعام: 107، 108 )
اور تو مشرکوں سے منہ پھیر لے اور اگر اللہ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے.نبی لوگوں پر داروغہ کے طور پر مقررنہیں کیا گیا
اللہ تعالیٰ بار بار کھول کر فرماتا ہے کہ نبی کا کام صرف سمجھانا ہے وہ لوگوں پر داروغہ
کی طرح متعین نہیں کیا گیا کہ وہ ضرور ان کو اسلام لانے یا اسلام میں رہنے کے لئے مجبور
کرے یا ان سے اس کے متعلق کوئی باز پرس کرے.چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:.فَذَكِّرُ ۖ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِرَةٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَّيْطِرٍ (الغاشية:22، 23 )
پس نصیحت کر کہ تو تو صرف نصیحت کرنے والا ہے.تو ان لوگوں پر داروغہ کے طور پر مقرر
نہیں ہے.
Page 28
25
پھر فرماتا ہے:.نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكَرُ
بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ (46:3)
ہم ان کی باتوں سے خوب واقف ہیں اور تو ان پر ایک جابر بادشاہ کے طور پر مقرر نہیں
کیا گیا.سو تو قرآن کے ساتھ صرف اس کو نصیحت کر جو میرے عذاب کی پیشگوئیوں
سے ڈرتا ہے.پھر فرماتا ہے:.وَلَوْ شَاءَ اللهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا
وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكيل (الانعام: 108) ٥ '
اور اگر اللہ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے اور ہم نے تجھے ان پر محافظ نہیں مقرر کیا اور نہ تو ان
پر نگران ہے.ان آیات سے اور اسی مضمون کی بہت سی دوسری آیات سے صاف ظاہر ہوتا ہے
کہ نبی کا یہ کام نہیں کہ وہ لوگوں پر بطور محافظ اور داروغہ کے مقرر ہو اور ان کو جبر سے اسلام
پر یہ
میں داخل کرے اور جو داخل ہو چکے ہوں ان کو بھٹکنے سے روکے رکھے.اس کا کام صرف
سمجھا دینا ہے اور بس.اور جب خود نبی کا یہ کام نہیں کہ وہ کسی رنگ میں جبر سے کام لے تو
اس کے اتباع کس طرح جبر سے کام لے سکتے ہیں.نبی کو ایمان اور کفر کی جزا سزا سے کوئی سروکار نہیں
حامیان دربار کابل اس بات کے مدعی ہیں کہ اسلام صرف ارتداد اور محض ارتداد
کے لئے قتل کی سزا مقرر کرتا ہے مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نبی کو اس امر سے کوئی تعلق نہیں کہ
وہ کسی کے کفر پر کسی کو سزا دے یہ خدا کا کام ہے جس کو چاہے معاف کرے اور جس کو چاہے
Page 29
26
سزا دے.چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:.لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ
فَإِنَّهُمْ ظُلِمُونَ (ال عمران: 129 )
(اے پیغمبر) تیرا اس معاملہ میں کچھ دخل نہیں یہ سب معاملہ خدا کے ہاتھ میں ہے چاہے
تو ان پر فضل کرے اور چاہے تو ان کو عذاب دے دے کیونکہ وہ ظالم ہیں.إِنَّ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا
آمُرُهُمْ إِلَى اللهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (الانعام:160)
جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہ در گروہ ہو گئے ہیں تیرا ان سے
کچھ تعلق نہیں ہے.ان کا معاملہ تو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے پھر جو کچھ وہ کرتے تھے
وہ اس کی انہیں خبر دے گا.اسلام مذہبی آزادی کی تعلیم دیتا ہے
مولوی ظفر علی خاں صاحب لکھتے ہیں کہ آزادی ضمیر کا خیال افرنجیت ہے جو مغربی
ممالک سے مسلمانوں میں داخل ہوئی.یہ ایک مستعار خیال ہے جو مسلمانوں نے مغرب
سے سیکھا.لیکن مولوی ظفر علی خاں صاحب کو معلوم ہونا چاہئیے کہ ضمیر کی آزادی کا اصول
مغرب کی ایجاد نہیں بلکہ یہ وہ اصول ہے جو سب سے پہلے قرآن شریف نے دنیا کو
سکھایا.آسمان کے نیچے صرف ایک ہی الہامی کتاب ہے جو ضمیر کی آزادی کے اصولوں کو
نہایت ہی مضبوط بنیاد پر قائم کرتی ہے.مذہبی آزادی کے متعلق آج سے 13 سوسال
پہلے جو تعلیم قرآن شریف میں دی گئی اس کی نظیر کسی اور الہامی یا غیر الہامی کتاب میں نہیں
پائی جاتی.اگر مغرب نے ضمیر کی آزادی کا سبق سیکھا ہے تو وہ مسیحیت کے حامیوں کے
تشد داور ظلم اور تعدی سے سیکھا ہے.مذہب کے نام پر مغربی لوگوں پر نا قابل بیان ظلم کئے
Page 30
27
گئے اور طرح طرح کے عذابوں کے ذریعہ ان کو دکھ دیا گیا اور قتل کیا گیا جس کا برعکس نتیجہ یہ
ہوا کہ لوگوں
کو مذہبی تشدد سے نفرت پیدا ہوگئی اور مذہبی آزادی کی قدر ان کے دلوں میں
قائم ہوگئی.یہ سبق انہوں نے مسیحیت سے نہیں سیکھا بلکہ مسیحی بزرگوں کی خونریر یوں اور
جفا کاریوں سے حاصل کیا لیکن ہم اس سبق کے لئے کسی انسان کے ممنون نہیں بلکہ ہمارا خدا
اپنی کتاب میں ہمیں اس اصول کی تعلیم دیتا ہے دیکھو اس بارے میں قرآن شریف کی تعلیم
کیسی کھلی کھلی اور واضح ہے.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:.إنَّ هذه تَذْكِرَةٌ ، فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا (المزمل:20)
یہ باتیں نصیحت کی ہیں پس جو چاہے اپنے پروردگار کی طرف پہنچنے کا راستہ اختیار
کرے.بعینہ یہی الفاظ سورۃ دھر میں بھی موجود ہیں.پھر فرماتا ہے:.كَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ ﴿ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ (المدثر: 56:55)
ہرگز ایسا نہیں کیونکہ قرآن تو سرا سر نصیحت ہے، پس جو چاہے اس کو سوچے سمجھے.پھر فرماتا ہے:.وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَنْ شَاء فَلْيُؤْمِن وَمَنْ شَاء فَلْيَكْفُرُ (الكهف: 30)
اے پیغمبر! ان لوگوں سے کہو کہ یہ قرآن بر حق تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل ہوا
ہے پس جو چاہے مانے اور جو چاہے نہ مانے.پھرفرماتا ہے:.قُلِ اللَّهَ أَعْبُدَ مُخْلِصًا لَّهُ دِينِي فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِ (الزمر:16:18)
اے پیغمبر! ان لوگوں سے کہو کہ میں تو خدا ہی کی فرمانبرداری مد نظر رکھ کر اسی کی عبادت
کرتا ہوں.رہے تم سو اس کے سوا جس کو چاہو پو جو.پھر فرماتا ہے:.قُلْ يَا يُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَ كُمُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ ۚ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي
لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ (يونس: 109)
Page 31
28
اے پیغمبر ! (صلی اللہ علیہ وسلم ) ان لوگوں سے کہہ دو کہ اے لوگو جوحق بات تھی وہ تو
تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس آ چکی.پس جس نے راہ راست اختیار
کی تو اپنے ہی فائدہ کے لئے اس کو اختیار کرتا ہے اور جو بھٹکا تو وہ بھٹک کر کچھ اپنا ہی
کھوتا ہے اور میں تم پر کچھ ٹھیکہ داروں کی طرح تو مسلط ہوں نہیں.پھر فرماتا ہے.وَاَنْ اَتْلُوا الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ
إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنْذِرِينَ (النمل: 93)
مجھ کو یہ حکم ملا ہے کہ میں لوگوں کو قرآن پڑھ کر سناؤں پس جو راہ پر آ گیا تو وہ اپنے ہی
بھلے کو راہ پر آتا ہے اور جو گمراہ ہوا تو تم کہہ دو کہ جہاں خدا نے اور ڈرانے والے بھیجے
ہیں میں بھی ان ڈرانے والوں میں سے ایک ڈرانے والا ہوں ، اور بس.ان سب آیات سے یہ امر بخوبی واضح ہو جاتا ہے کہ دین کے معاملہ میں اللہ تعالیٰ
نے انسانوں کو آزادی دے رکھی ہے.اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کھول کر بیان فرما دیا
ہے
اور راہ راست پر چلنے کے فوائد اور کج راہ پر چلنے کے نقصانات بھی بوضاحت بیان فرما دیئے
ہیں اس کے بعد انسان اگر چاہے تو ہدایت کی راہ کو اختیار کرے اور چاہے تو دوسری راہ
اختیار کرے.ایسی تعلیم کی موجودگی میں یہ کس طرح کہا جا سکتا ہے کہ اسلام ہی تعلیم دیتا ہے
کہ جو لوگ اسلام سے مرتد ہونا چاہیں ان کو تلوار کے زور سے اسلام میں رہنے کے لئے
مجبور کیا جاوے اور جو لوگ اسلام میں رہنا منظور نہ کریں ان
کو فورا قتل کر دیا جائے.کیا ایسی
قابل نفرت تعلیم ایک لمحہ کے لئے بھی قرآن جیسی کتاب کی طرف منسوب کی جاسکتی ہے جو
بآواز بلند کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کی راہیں واضح کر کے بیان فرما دی ہیں
اور دونوں راہوں کو اختیار کرنے کے نتائج بھی کھول کر بیان فرما دیے ہیں.پس اب ہر
ایک شخص کا اختیار ہے چاہے تو حق کی راہ اختیار کرے اور چاہے تو باطل کی پیروی کرے.
Page 32
29
اس کے اپنے عمل کے مطابق اس کو بدلہ مل جائے گا.دین کے معاملہ میں کوئی جبر نہیں
اب میں چند آیات قرآنی اس مضمون کی پیش کرتا ہوں کہ دین کے معاملہ میں جبر
سے کام لینا نا جائز ہے اور اللہ تعالیٰ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر کرتے ہوئے
فرماتا ہے:.قَالَ الْمَلَا الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يُشْعَيْبُ
وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ
اَوَلَوْ كُنَّا كُرِهِينَ (الاعراف: 89)
شعیب کی قوم میں جو لوگ رودار اور مغرور تھے بولے کہ اے شعیب ہم تجھ کو اور جو تیرے
ساتھ ایمان لائے ہیں ان کو اپنی بستی سے نکال دیں گے یا یہ ہوگا کہ تم لوگ ہمارے
مذہب میں لوٹ آؤ گے.شعیب نے کہا کیوں جی! اگر ہم تمہارے دین کو دل سے
نا پسند کرتے ہوں پھر بھی زبر دستی تمہارے مذہب میں آملیں؟
اس آیت کریمہ میں خدا تعالیٰ کا ایک پاک نبی مذہب کی تبدیلی کے متعلق ایک
اصول بیان کرتا ہے.جب حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی جماعت سے ان کی بستی
کے ذی اقتدار رئیس اس امر کا مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے آبائی مذہب میں واپس لوٹ
آویں ورنہ وہ ان کے حق میں یہ حکم جاری کریں گے کہ ان کو بستی سے نکال دیا جاے.تو
حضرت شعیب علیہ السلام ان عمائد سے ایک سوال کرتے ہیں وہ ان سے پوچھتے ہیں.اگر
ہم دل میں تمہارے دین کو نا پسند کرتے ہوں تو کیا پھر بھی ہم اس میں اپنی مرضی کے خلاف
اکراہ و جبر داخل ہو سکتے ہیں؟ یہاں حضرت شعیب اپنی قوم کے مقابل میں ایک عقلی دلیل
پیش کرتے ہیں.وہ فرماتے ہیں کہ مذہب کا تعلق تو دل سے ہے اگر ہمارے دل تمہارے
Page 33
30
مذہب کو نا پسند کرتے ہوں تو پھر ہم سے اس امر کا مطالبہ کرنا کہ ہم اپنی مرضی کے خلاف
تمہارے مذہب کی طرف لوٹ آئیں ایک غیر معقول فعل ہے.اس دلیل سے یہ نتیجہ نکلتا
ہے کہ کسی شخص کو اس کی مرضی کے خلاف کسی دین میں داخل ہونے کے لئے مجبور کرنا ہرگز
جائز نہیں.66
پس اگر اولو كُنَّا کرِهِينَ “ کی دلیل درست ہے تو مسلمانوں کے لئے بھی یہ
نا جائز ہے کہ وہ اسلام سے ارتداد اختیار کرنے والے کسی انسان کو یہ کہیں کہ لنَقْتُلَنَّكَ
يَافُلَانُ اَوْلَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا ، بلکہ قتل کرنا تو کجاوہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے لَنُخْرِجَنَّكَ
يَافُلَانُ مِنْ قَرْيَتِنَا اَوْلَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا ، کیونکہ اگر وہ ایسا کہیں گے تو وہ ان کے جواب
میں کہ سکتا ہے اَوَلَوْ كُنَّا كَرِهِین “.خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر حضرت شعیب کی یہ دلیل
اپنے اندر کوئی سچائی اور معقولیت رکھتی ہے تو مرتد کے قتل کا فتویٰ غلط ہے اور اگر مرتد کو محض
ارتداد کے لئے قتل کرنے کا فتویٰ درست ہے تو حضرت شعیب کی اَوَلَوْ كُنَّا كُرِهِينَ “ والی
دلیل نعوذ باللہ غلط ٹھہرتی ہے.پھر دیکھو اللہ تعالیٰ اس درد کا ذکر کرتے ہوئے جو آنحضرت ﷺ کو اپنی قوم کے
متعلق تھا فرماتا ہے :.وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيْعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ
حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِيْنَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْ مِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۖ وَيَجْعَلْ
الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ (يونس: 100 ،101)
اے پیغمبر! تمہارا پروردگار چاہتا تو جتنے آدمی روئے زمین پر ہیں سب کے سب ایمان
لے آتے.تم لوگوں کو مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ سب کے سب ایمان لے آئیں اور
اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی شخص ایمان نہیں لا سکتا اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر گندگی ڈال دیتا
ہے جو عقل کو کام میں نہیں لاتے.
Page 34
31
ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دین کے معاملہ میں جبر نہیں ہوسکتا.اگر جبر کا
اصول درست ہوتا تو خدا تعالیٰ کو کیا ضرورت تھی کہ وہ اس کام کو لوگوں کے سپر د کرتا.وہ اگر
چاہتا تو روئے زمین کے تمام لوگوں کو خود مسلمان بنا دیتا.اس معاملہ میں اس کو انسانوں کی
امداد کی ضرورت نہ تھی.پھر فرماتا ہے جبر سے کوئی کسی کو کس طرح مسلمان بنا سکتا ہے.ایمان کی توفیق دینا تو خدا تعالیٰ کے اختیار میں ہے اور جو لوگ خداداد عقل سے کام نہیں لیتے
ان کو ایمان کی توفیق نہیں دی جاتی.پس یہ آیات بھی دین کے معاملہ میں جبر کرنے سے روکتی ہیں اور اس کو ایک
بیہودہ فعل قرار دیتی ہیں.کیونکہ اس سے وہ غرض پوری نہیں ہوسکتی جس کے لئے جبر کا
استعمال کیا جاتا ہے اور جس طرح ایسے شخص کے لئے جبر کرنا نا جائز ہے جو کبھی مسلمان نہیں
ہوا اسی طرح اس شخص کے لئے بھی جبر نا جائز ہونا چاہیے جو اسلام لانے کے بعد کفر اختیار
کرتا ہے.پیدائشی کافر بھی کافر ہے اور مرتد بھی کافر ہے اور اگر پیدائشی کافر کے لئے
جبروا کراہ درست نہیں تو مرتد کے لئے بھی درست نہیں ہوسکتا.یہ نہیں ہوسکتا کہ ایک
صورت میں جبرنا جائز ہو اور دوسری صورت میں جبر جائز ہو.جبر ہر صورت میں نا جائز ہونا
چاہئیے.جبرا گر بُری چیز ہے تو دونوں صورتوں میں بُری ہونی چاہئیے.پیدائشی کافر کی
صورت میں جبر کیوں ناجائز تھا ؟ اسی لئے کہ جبر کے ذریعہ کسی کے دل میں اسلام کا نور
داخل نہیں کیا جا سکتا اور یہی وجہ مرتد کی صورت میں بھی موجود ہے.کیونکہ جیسا پیدائشی کافر
کو جبر وا کراہ کے ذریعہ ہدایت نہیں دی جاسکتی اسی طرح مرتد کی صورت میں بھی جبر وا کراہ
ہدایت کا ذریعہ نہیں ہو سکتا.پس اگر پیدائشی کافر کے لئے جبر نا جائز ہے تو مرتد کے لئے بھی
جبر اسی طرح ناجائز ہونا چاہیے.فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرُ
(الكهف:30) جیسا پیدائشی کا فر پر چسپاں ہوتا ہے ویسا ہی مرتد پر.میں قرآن شریف کی بہت سی آیات پیش کر چکا ہوں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ
Page 35
32
اسلام دین کے معاملہ میں جبر کونا جائز قرار دیتا ہے اور وہ سب آیات ایسی واضح اور تین
ہیں کہ ان میں کسی قسم کے شبہ کی گنجائش نہیں لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ بعض لوگ جبر کی
تعلیم کی طرف جھک جائیں گے اور وہ دین کے لئے جبروا کراہ کو جائز قرار دیں گے اس
لئے اللہ تعالیٰ نے اصول اور قاعدہ اور حکم کے رنگ میں ایک نہایت ہی زبر دست اور چٹان
کی طرح مضبوط آیت قرآن شریف میں نازل فرمائی ہے جو ہر ایک ایسے شخص کے دعوی کو
جوز مین میں جبر کے جواز کا قائل ہو پاش پاش کر دیتی ہے.وہ قطعی اور فیصلہ کن حکم یہ ہے.لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ (البقرة: 257)
دین میں زبر دستی کا کچھ کام نہیں ( ترجمہ مولوی نذیراحمد صاحب دہلوی)
دیکھو یہ کیسے کھلے کھلے اور کیسے واضح الفاظ میں اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ دین
میں جبر و اکراہ کو کوئی دخل نہیں.قرآن شریف میں اس واضح اور صریح حکم کے موجود ہوتے
ہوئے کس طرح کوئی شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اسلام قتل کی دھمکی دے کر لوگوں کو ارتداد
سے روکتا ہے کیا وہ دین جو لا اکراہ فی الدین کا اعلان کرتا ہے یہ تعلیم دے سکتا ہے کہ
جبر سے لوگوں کو مسلمان بنایا جائے اور وہ لوگ جو اسلام لانے کے بعد اسلام سے برگشتہ
ہونا چاہیں ان کو جبر سے مسلمان رکھا جاوے.یہ آیت کریمہ اپنے منطوق میں ایسی واضح
اور بین ہے کہ جو لوگ دین میں جبر وا کراہ کے قائل ہیں وہ اس بات پر مجبور ہوئے ہیں کہ
اس آیت کریمہ کو منسوخ قرار دیں.ان کا اس آیت کریمہ کو منسوخ قرار دینا صاف ظاہر
کرتا ہے کہ ان کے نزدیک یہ آیت شریفہ کھلے طور پر جبر واکراہ سے روکتی تھی اور کوئی
معقول توجیہ ایسی نہیں ہو سکتی تھی جس کے رو سے یہ کہا جاسکے کہ یہ آیت اکراہ کی مانع نہیں
ہے اس لئے وہ اس کو منسوخ قرار دینے کے لئے مجبور ہو گئے.لیکن جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں قرآن شریف کوئی حکم نہیں دیتا جس کی دلیل
اور حکمت بھی وہ ساتھ ہی بیان نہیں فرماتا.چنانچہ اس حکم کی دلیل بھی اس حکم کے ساتھ ہی
Page 36
33
بیان
فرما دی گئی ہے جو یہ ہے کہ
قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ (البقرة: 257)
یعنی جبر کا تو ایک ہی مقام ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ جو سمجھ نہ سکے اس پر جبر کیا جاتا ہے
جیسا کہ بچہ کی صورت میں کیونکہ اس میں ابھی سمجھنے کی قابلیت پیدا نہیں ہوتی مگر اللہ تعالیٰ
فرماتا ہے کہ یہاں وہ صورت نہیں ہے.یہاں یہ حال ہے کہ قد تبين الرشد من الغى
ہدایت گمراہی سے الگ ظاہر ہو چکی ہے.یعنی اب ہدایت اور گمراہی کی راہیں بالکل
واضح اور تین ہو گئی ہیں اور ہر ایک کے لئے جو سمجھنا چاہے ہدایت کا طریق گمراہی سے
بالکل الگ ہو گیا ہے اور ان دونوں کے درمیان تمیز کرنے میں کوئی دقت باقی نہیں رہی اس
لئے جبر کی ضرورت بھی باقی نہیں رہی.پس دین کے معاملہ میں جبر کرنا نا جائز ہے.یہاں یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ لا اکراہ فی الدین کا حکم جنگی تعلیم کے بعد دیا گیا
ہے.اس سے پہلے قتال کے احکام اور اس کی تعلیم بیان فرمائی گئی ہے.پس نہ صرف اس
آیت کریمہ کا مضمون بلکہ اس کا مقام بھی یہی ظاہر کرتا ہے کہ یہ آیت کریمہ جبر وا کراہ کی
ممانعت کے لئے نازل ہوئی ہے.مذہبی اعتقاد کی بنا پر تکلیف دینا انبیاء کے دشمنوں کا شیوہ ہے
اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں گزشتہ انبیاء اور ان کی قوموں کے تذکرے اس
لئے بیان فرمائے ہیں کہ ہم ان سے عبرت حاصل کریں.چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:.لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ (يوسف: 112)
ان لوگوں کے ذکر میں عظمندوں کے لئے ایک عبرت کا نمونہ موجود ہے.پس اللہ تعالیٰ اپنی پاک کتاب میں مومنوں کا حال بھی بیان کرتا ہے اور کفار کا بھی ،
اور اس بیان سے منشاء یہ ہے کہ ہم مومنوں کے نمونہ پر چلیں اور ان راہوں سے پر ہیز کریں
Page 37
34
جن پر مومنوں کے دشمن ہمیشہ قدم مارتے چلے آئے.گذشتہ لوگوں کے جن کاموں کی
اللہ تعالیٰ تحسین فرماتا ہے وہ نیک کام ہیں اور ہمارا فرض ہے کہ ہم انہیں اختیار کریں اور
گذشتہ قوموں کے جن افعال کو اللہ تعالیٰ ظلم قرار دیتا ہے وہ کام ہمیشہ ظلم ہی سمجھے
جائیں گے اور جو شخص ان کا ارتکاب کرے گا خواہ وہ کافر کہلا تا ہو یا اپنی تئیں مومن کا خطاب
دیتا ہو وہ خدا کے نزدیک ظالم ہے.ظلم ہمیشہ ظلم ہے خواہ اس کا مرتکب زید ہو یا بکر.اگر
مذہبی عقائد کے لئے کسی کو دکھ دینا کفار کے لئے ایک ظلم ہے تو مسلمانوں کے لئے بھی ایسا
کرنا ظلم ہے.خدا تعالیٰ نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ مذہبی تبدیلی پر کفار کے لئے تو یہ ظلم ہے کہ
وہ کسی کو تکلیف دیں مگر مومنوں کے لئے ایسا کرنا نہ صرف جائز بلکہ ضروری ہے.یہ بالکل
انصاف سے بعید ہے کہ کفار ایک کام کریں جو ظلم کہلائے اور بعینہ وہی کام مومن کریں تو وہ
نہ صرف جائز سمجھا جائے بلکہ ضروری قرار دیا جائے.فرض کرو ایک ہندو ریاست ہے اور اس کا راجہ ایک خود مختار حاکم ہے جس نے یہ
قانون جاری کر رکھا ہے کہ جو شخص ہندو مذہب کو چھوڑ کر اسلام قبول کرے اسے فورا قتل کر
دیا جائے، اب بتائیے ہندو راجہ کا یہ فعل ظلم ہے یا نہیں ؟ کیا تمہاری کانشنس اس بات کی
شہادت نہیں دیتی کہ وہ راجہ بڑا ہی ظالم اور سفاک ہے جو اسلام لانے پر لوگوں کو قتل کر
دیتا ہے؟ کیا تم یہ نہیں کہو گے کہ وہ انسان نہیں بلکہ ایک درندہ ہے؟ کیا تم اس کے فعل کو ایک
وحشیانہ فعل نہیں کہو گے؟ کیا تمہاری فطرت اس کے خلاف جوش میں نہیں آئے گی ؟ اور کیا
تمہاری طبیعت نفرت اور غضب سے نہیں بھر جائے گی؟ کیا تم اس کے فعل پر اظہار نفرین
نہیں کرو گے؟ میں اس سے بھی اتر کر آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر وہ راجہ اپنی رعایا کے
لوگوں کو اس لئے قتل کرتا ہے کہ وہ آریہ مذہب اختیار کرتے ہیں یا مسیحی تثلیث اور کفارہ پر
ایمان لا کر بپتسمہ لیتے ہیں تو مجھے سچ سچ بتاؤ تم اس کے اس فعل کو کیسا سمجھو گے؟ تم اپنی ضمیر کو
جگا کر پوچھو جوضرور یہی فتویٰ دے گی کہ وہ راجہ ایک ظالم انسان ہے اور اس کا اس لئے
Page 38
35
لوگوں کو قتل کرنا کہ وہ کیوں ہندو مذہب کو چھوڑ کر دوسرا مذ ہب اختیار کرتے ہیں جو سخت
سنگدلی اور پرلے درجہ کی بے رحمی ہے.اس کو کوئی حق نہیں کہ لوگوں کے مذہب کے معاملہ
میں دخل دے.کسی مذہب کے قبول کرنے یا نہ قبول کرنے کے بارے میں اسے چاہئیے تھا
کہ وہ لوگوں کو آزاد چھوڑ دیتا تا جس مذہب کو وہ سچا سمجھتے اسے اختیار کرتے.پس میں پوچھتا ہوں کہ جو بات دوسروں کے لئے ناجائز ہے وہ تمہارے لئے کس
طرح جائز ہوگی؟ یہ کیونکر ہوا کہ جس بات کو تم دوسرے لوگوں کے لئے ظلم عظیم کہتے تھے اور
جس کوسُن کر تمہارے چہرے سرخ ہو جاتے تھے اور تمہاری آنکھوں میں خون اتر آتا تھا وہ
تمہارے لئے کیوں عین صواب ہو گیا ؟ یہ کس طرح ہوسکتا ہے کہ ایک فعل کو جب دوسرے
لوگ کریں تو وہ نہایت ہی وحشیانہ فعل اور خونخواری کہلائے اور جب تم اسی کام کو کرو تو وہ
نہایت مہذبانہ اور شریفانہ ہو جائے ؟ آج اگر کوئی ہندو ریاست ایسے لوگوں کو جو جنم کے
ہندو ہوں اور بعد میں اسلام لے آئیں گرفتار کرنا اور پھر سنگسار کرنا شروع کر دے تو کیا
مولوی ظفر علی خاں صاحب ”زمیندار“ کی ایڈیٹری کی کرسی پر بیٹھ کر اس راجہ کے خلاف
نہایت پُر زور پُر جوش مضمون نہیں لکھیں گے اور کیا اپنے قلم کا سارا زور اور اپنی ساری قوت
بیان اس کے اس فعل کو خلاف انسانیت اور ظالمانہ قرار دینے میں خرچ نہیں کر دیں گے؟
اور کیا اس کے خلاف ایک ہنگامہ قیامت برپا نہ کر دیں گے؟ لیکن اگر مولوی صاحبان
کو جواب میں یہ کہا گیا کہ اس راجہ نے بالکل اسی اصول پر کام کیا ہے جس پر امیر صاحب
کابل نے کیا ہے تو مولوی ظفر علی خاں صاحب دنیا کو کیا جواب دیں گے؟ کیا مولوی
صاحب یہ کہیں گے کہ چونکہ امیر صاحب کا بل کا مذہب سچا مذہب ہے اس لئے اس کے
لئے نہ صرف جائز بلکہ واجب ہے کہ جو شخص اس کے مذہب کو چھوڑے وہ اسے قتل
کر دے.لیکن نیپال کے راجہ یا چین کی حکومت یا روس کی گورنمنٹ کا مذہب سچا مذہب
نہیں ہے اس لئے اگر وہ کسی کو مذہب کی تبدیلی سے روکیں اور ایسی تبدیلی کرنے والوں کو
Page 39
36
سنگسار کریں تو وہ ظالم ہیں.کیا کوئی عقلمند انسان مولوی صاحب کے اس جواب سے تسلی پا
سکے گا؟ نیپال کے راجہ کو اور چین کی حکومت کو اپنے مذہب کی صداقت کا ایسا ہی یقین ہے
جیسا کہ امیر صاحب افغانستان کو یقین ہے.پس اگر امیر صاحب افغانستان کو یہ حق پہنچتا
ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو سنگسار کر دیا کریں جو اس کے خیال میں اس کے مذہب سے ارتداد
اختیار کریں تو نیپال کے راجہ اور گورنمنٹ چین کو بھی حق پہنچتا ہے ہے کہ وہ بھی ایسے لوگوں
کو قتل کر دیا کریں جو ان کے آبائی مذہب سے ارتداد اختیار کریں.جس اصول پر ایک ہندو
راجہ کے لئے ناجائز ہے کہ وہ کسی کو مذہب کی تبدیلی سے رو کے اُسی اصول پر ایک مسلمان
امیر کے لئے بھی ناجائز ہے کہ وہ کسی کی تبدیلی مذہب میں مزاحم ہو.تم ایک ہندو راجہ کو
کیوں ظالم کہتے ہو جب وہ کسی ہندو کو اسلام قبول کرنے سے روکتا ہے؟ کیا اسی لئے کہ
ہندو مذہب ایک جھوٹا مذہب ہے اور اسلام ایک سچا مذہب ہے؟ کیا یہی دلیل ہے جو تم
ہندو راجہ کے سامنے یا عقلمند طبقہ کے سامنے اس کے ظلم کو ثابت کرنے کے لئے پیش کرو
گے؟ کیا تم ہندو راجہ کو یہ کہو گے کہ تم اس لئے ظالم ہو کہ تمہارا مذ ہب جھوٹا ہے اور اسلام سچا
ہے اور تم لوگوں کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ جھوٹے مذہب کو چھوڑ کر سچا دین اختیار کریں؟
تم کس دلیل سے اس ہندو راجہ کا ظلم لوگوں پر اور خود اس راجہ پر واضح کرو گے؟ تم کبھی اپنی
دلیل کو اس پیرا یہ میں پیش نہیں کرو گے کہ کسی انسان
کو حق نہیں کہ وہ لوگوں کو جھوٹے دین سے
بچے دین کی طرف آنے سے رو کے بلکہ تم یہ کہو گے کہ کسی انسان کو حق نہیں کہ وہ کسی شخص کو
ایک دین سے دوسرے دین میں آنے سے روکے.پس اگر یہ دلیل درست ہے ( اور ضرور
درست ہے ) تو جیسا کہ راجہ نیپال کو حق نہیں کہ وہ کسی ہندو کوعیسائی، بدھ یا مسلمان ہونے
سے روکے اور ایسا کرنے والوں کو سنگسار کرے، ایسا ہی امیر صاحب کابل اور کسی اور بادشاہ
کو یہ حق نہیں کہ وہ کسی شخص کو محض ارتداد کی سزا میں قتل یا سنگسار کرے.ایسا کرنا نہ صرف اسلام کی تعلیم کے خلاف ہے بلکہ اسلام کو سخت نقصان پہنچانا
Page 40
37
ہے.کیونکہ اگر ایک مسلمان بادشاہ کسی شخص کو محض اس لئے قتل اور سنگسار کرنے کا حکم دیتا
ہے کہ اس نے ایک غیر مذہب اختیار کیا ہے تو غیر مذاہب کی سلطنتیں اس کے مقابل میں
ان لوگوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کریں گی جو ان کی رعایا میں سے اسلام قبول کرنا چاہیں
گے اور کسی اسلامی مبلغ کو اجازت نہیں دیں گی کہ ان کے علاقہ میں قدم بھی رکھے جس کا
نتیجہ یہ ہوگا کہ اسلام کی اشاعت رک جائے گی.پس مرتدین کے لئے محض ارتداد کی سزا میں قتل کا فتویٰ دینے والے نہ صرف
قرآن شریف کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں بلکہ اسلام کو سخت نقصان پہنچاتے
ہیں.وہ اسلام کے دوست نہیں بلکہ دشمن ہیں.خدا تعالی اسلام کو ایسے دوستوں کے
ہاتھوں سے بچائے.آمین ثم آمین !
قرآن شریف کو اوّل سے آخر تک پڑھ جاؤ.تم یہ تو جا بجا لکھا ہوا دیکھو گے کہ خدا
کے نبیوں کے دشمن بڑے ظالم تھے.وہ دین کے معاملہ میں جبر سے کام لیتے تھے اور جبراً
لوگوں کا اپنا دین چھوڑنے سے روکتے تھے لیکن یہ تم کہیں بھی لکھا ہوا نہ پاؤ گے کہ مومنوں کی
جماعتیں بھی جبر سے کام لیتی تھیں اور جو لوگ سچے دین سے منہ پھیر کر بت پرستی یا شرک کی
طرف یا کسی اور گمراہی کی راہ یا جھوٹے دین کی طرف رجوع کرتے تھے ان کو مومن قتل اور
سنگسار کر دیا کرتے تھے.سارے قرآن شریف کو پڑھ جاؤ تم کوئی ایسی مثال نہیں پاؤ
گے.پھر تم قرآن شریف میں یہ تو لکھا ہو اپاؤ گے کہ انبیاء کے دشمن بڑے ظالم تھے کیونکہ وہ
دین کے معاملہ میں جبر واکراہ سے کام لیتے تھے لیکن یہ کہیں نہیں لکھا ہوا پاؤ گے کہ مسلمانوں
کے لئے نہ صرف جائز بلکہ ضروری ہے کہ وہ جبر وا کراہ سے کام لیں بلکہ برخلاف اس کے
ہم قرآن شریف میں یہ کھلا کھلا اور صریح اعلان دیکھتے ہیں کہ
لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ (البقرة: 257)
کہ دین کے معاملہ میں کسی قسم کا جبر جائز نہیں.
Page 41
38
آؤ ہم قرآن شریف کی طرف رجوع کریں اور گزشتہ امتوں کے حالات کا جو
ہمارے لئے بطور سبق بیان کئے گئے ہیں مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ مذہب کی تبدیلی پر دکھ
دینا کن لوگوں کا شیوہ رہا ہے؟ مومنین کا یا کفار کا؟ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر
ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جس قدر بڑے بڑے نبی اور رسول گزرے ہیں میں
ان میں سے اکثر کے حالات کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں تا آپ کو معلوم ہو کہ امراء کابل
نے نعمت اللہ خان مرحوم اور دیگر شہداء جماعت احمدیہ کوسنگسار کر کے کس گروہ میں اپنی تیں
داخل کیا ہے اور کس جماعت کے نقش قدم پر گامزن ہوئے ہیں؟
حضرت آدم علیہ السلام کے بعد پہلا اولوالعزم جن کا ذکر قرآن شریف میں تفصیل
کے ساتھ موجود ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام ہیں.حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے
کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور مجھے قبول کرو.اور پھر فرماتے ہیں:.إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ (الشعراء: 116)
میں تو لوگوں کو صاف طور پر ڈرانے والا ہوں اور بس.میرا یہ کام نہیں کہ میں کسی کو جبراً اپنے دین میں داخل کروں.مگر ان کی قوم کہتی ہے.لَبِنْ لَّمْ تَنْتَهِ يُنُوْحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُوْمِينَ - (الشعراء: 117 )
اے نوح! اگر تم اپنے اس نئے مذہب سے باز نہ آؤ گے تو ضرور سنگسار کر دیئے جاؤ گے.اب دونو کے طریق کا مقابلہ کرو.حضرت نوح علیہ السلام تو اپنی قوم کو اپنے نئے
پیغام کی طرف بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں میرا کام صرف اللہ کا پیغام پہنچادینا ہے اور بس.مگر ان کی قوم ان کو سنگساری کی دھمکی دیتی ہے.اب آپ خود ہی فیصلہ فرمالیں کہ ان
دونوں راہوں میں سے کون سی راہ خدا کی رضا کی راہ ہے اور کونسی راہ وہ ہے جو خدا تعالیٰ کے
نزدیک بُری ہے اور غضب الہی کو بھڑکاتی ہے.اور آپ ساتھ ہی یہ بھی فیصلہ فرمالیں کہ ان
دونوں میں سے کونسی راہ ہے جو امراء اور علماء کا بل نے اختیار کی ؟
Page 42
39
پھر حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جو بڑا عظیم الشان نبی دنیا میں آیا وہ حضرت
ابراہیم علیہ السلام تھے.آؤ ہم دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رویہ کیسا تھا اور ان
کی قوم نے کیسا رویہ اختیار کیا ؟ اور پھر اس بات کا فیصلہ کریں کہ اس زمانہ کے مسلمان
ان دونو رویوں میں سے کس رویہ کو اختیار کر رہے ہیں اور امیر کابل نے کونسا رویہ اختیار
کیا ، ابراهیمی یا نمرودی؟
حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک نوجوان آدمی ہیں جو اپنی قوم کے جھوٹے معبودوں
کے عجز اور بے بسی کو ظاہر کرنے کے لئے ان بتوں کو توڑتے ہیں جن کا متوتی ان کا اپنا
خاندان تھا اور ان کی قوم کے لوگ ٹوٹے ہوئے بتوں کا نظارہ دیکھ کر غضب میں آتے ہیں
اور پوچھتے ہیں کس نے ہمارے بت توڑے؟ وہ بڑا ہی ظالم اور بالفاظ مولوی ظفر علی خاں
صاحب بڑا ہی ” مفسد اور شریر النفس انسان ہے.اس پر بعض نے پتا دیا اور کہا
سَمِعْنَا فَى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ ابْرُ هِيمُ (الانبياء: 61)
وہ نو جوان جس کو ابراہیم کے نام سے پکارا جاتا ہے اس کو ہم نے ان بتوں کا تذکرہ
کرتے ہوئے سنا ہے.اور پھر وہ نوجوان اپنی قوم کے بزرگوں کے سامنے بلایا جاتا ہے اور سوال و جواب
میں جب وہ لوگ لا جواب اور شرمندہ ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں :.حَرِّقُوهُ (الانبياء: 69)
یعنی اس نوجوان کو آگ میں ڈال کر جلا دو.اسی طرح حضرت ابوالانبیاء کے اب آزر اپنی شفقت کا اظہار ان لفظوں
میں کرتے ہیں:.لَبِنْ لَّمْ تَنْتَهِ لَاَرْجُمَنَّكَ (مريم: 47)
اگر تو اپنے اس نئے مذہب سے باز نہ آیا تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا.
Page 43
40
اب دیکھو حضرت
ابراہیم علیہ السلام نے کیا راہ اختیار کی اور ان کی قوم نے کیا
طریق اختیار کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اپنی قوم کو ان کی اعتقادی اور عملی کمزوریوں
پر متنبہ کرتے ہیں مگر ان کی قوم ان کو آگ میں جلانے کا فیصلہ کرتی ہے اور ان کے اب آزر
سنگسار کرنے کی دھمکی دیتے ہیں.پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بعد حضرت موسی کلیم اللہ علیہ السلام کے
زمانہ کی طرف آؤ اور دیکھو وہاں ہمیں کیا نظارہ نظر آتا ہے حضرت موسیٰ و حضرت ہارون علیہا
الصلوۃ والسلام
کو تو حکم ہوتا ہے.إِذْهَبَا إِلى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى فَقُوْلَا لَهُ قَوْلًا لَّيْنًا لَّعَلَّهُ
يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشُى (طه: 45.44)
دونو فرعون کے پاس جاؤ.اس نے بہت سراٹھا رکھا ہے.پھر اس سے نرمی سے بات کرو
شاید وہ سمجھ جائے یا ڈرے.اس کے مقابل میں فرعون اور اس کی قوم کا عمل دیکھو.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:.فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ
وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَلٍ وَقَالَ فِرْعَوْنُ
ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ اِنّى اَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ
يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ (المؤمن: 27،26)
غرض کہ جب موسیٰ ہماری طرف سے حق لے کر فرعون، ہامان وغیرھما کے پاس آئے تو
انہوں نے حکم دیا کہ جولوگ موسی کے ساتھ ایمان لے آئے ہیں ان کے بیٹوں کو تو قتل
کر ڈالو اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دو، اور کافروں کی تدبیریں تو آخر کا رسب غلط ہی
ہو جاتی ہیں اور فرعون نے (اپنے درباریوں سے ) کہا کہ مجھے موسی کو قتل کرنے دو اور
وہ اپنے پروردگار کو اپنی امداد کے لئے بلائے.مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ
ا
Page 44
41
تمہارے دین کو الٹ پلٹ کر ڈالے یا ملک میں فساد نکال کھڑا کرے.پھر ان لوگوں کو مخاطب کر کے جو حضرت موسیٰ کا نشان دیکھ کر
ان پر ایمان لائے فرعون کہتا ہے :.اِنَّ هَذَا لَمَكْرُ مَّكَرْتُمُوهُ فِي
الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَا قَطِعَنَ أَيْدِيَكُمْ
وَاَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأَصَلْبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ قَالُوا إِنَّا إِلَى رَبَّنَا مُنْقَلِبُونَ
وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ أَمَشَابِايْتِ رَبَّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا
مُسْلِمِينَ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا
فِي الْأَرْضِ وَيَدْرَكَ وَالِهَتَكَ قَالَ سَنُقَتِلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْي
دو
نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ فَهِرُونَ (الاعراف: 128124)
ہو نہ ہو یہ تمہارا ایک فریب ہے، کہ شہر میں آکر یہ پاکھنڈ مچایا ہے تا کہ یہاں کے لوگوں کو
اس شہر سے نکال دو.سو تم کو اپنے کئے کا نتیجہ بھی تھوڑی دیر میں معلوم ہو جائے گا.میں
تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں الٹے کٹواؤں گا پھر تم سب کو سولی پر چڑھاؤں گا.وہ کہنے
لگے کہ ہم کو تو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور تو نے ہم میں قصور کیا پایا ہے صرف
یہ کہ جب ہمارے پروردگار کے نشان ہمارے سامنے ظاہر ہوئے تو ہم ان پر ایمان لے
آئے اور اب ہماری بس یہی دعا ہے کہ اے ہمارے پروردگار ہم پر صبر انڈیل دے اور اپنی
فرمانبرداری ہی کی حالت میں ہم کو اس دنیا سے اٹھالے.اور فرعون کے لوگوں میں سے
سرداروں نے فرعون سے کہا کہ کیا آپ اسے اور اس کی قوم کے لوگوں کو اسی حال پر رہنے
دیں گے کہ ملک میں فساد پھیلاتے پھریں اور وہ آپ سے اور آپ کے معبودوں سے
سرتابی کرتار ہے.فرعون بولا نہیں ہم ابھی ان کے بیٹوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ماریں گے اور ان
کی عورت ذات کو زندہ رکھیں گے اور ہم ان پر ہر طرح سے غالب ہیں.“
Page 45
42
متذکرہ بالا واقعات کو ان واقعات پر جو آج کل سرزمین کابل میں ظہور پذیر ہوئے
ہیں چسپاں کرو اور بتلاؤ کہ مومنین کے حالات کس جماعت پر چسپاں ہوتے ہیں اور کس نے
فرعون کا پارٹ ادا کیا؟ کن نوجوانوں نے وہ ثبات اور جان شاری دکھائی جو حضرت موسی
علیہ السلام کے زمانہ میں مومنین نے دکھائی تھی اور کس گروہ نے ان سے وہ سلوک کیا جو موسی
علیہ السلام کے زمانہ میں فرعون اور اس کے سرداروں نے مومنین سے کیا تھا؟
یہ واقعات قرآن شریف میں اس لئے بیان کئے گئے تھے کہ مسلمان ان سے
عبرت حاصل کریں اور وہ راہ اختیار نہ کریں جو پہلے زمانوں میں متکبر اور سرکش اور اپنی
طاقت پر گھمنڈ ر کھنے والے لوگ کیا کرتے تھے.مگر ہائے افسوس! بجائے اس کے کہ وہ ان
واقعات سے عبرت حاصل کر کے دشمنانِ حق کی راہوں سے اجتناب کرتے انہوں نے
وہی راہ اختیار کی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ میں نمرود نے اور حضرت موسی
علیہ السلام کے زمانہ میں فرعون اور اس کے سرداروں نے اور حضرت عیسی علیہ السلام کے
وقت میں یہود کے فریسیوں اور فقیہوں نے اختیار کی تھی.پھر میں کہتا ہوں کہ کابل کے سرداروں اور اراکین نے احمدی جماعت کے ساتھ
وہی رویہ اختیار کیا ہے جو مکہ کے عمائد نے صحابہ کی غریب جماعت کے ساتھ اختیار کیا تھا.اللہ تعالیٰ مہاجرین کی نسبت فرماتا ہے:.فَالَّذِيْنَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَ أُوذُوا فِي سَبِيْلِى
(ال عمران: 196 )
پس جن لوگوں نے ہمارے لئے اپنے دیس چھوڑے اور ہماری وجہ سے اپنے گھروں
سے نکالے گئے اور دکھ دیئے گئے.یہ آیت اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ جیسا کہ تاریخ سے ثابت ہے کہ غریب
مسلمانوں
کو عمائد مکہ نے اس قدر دکھ دیئے اور ان پر اس قدر ظلم کئے کہ وہ اپنے گھروں سے
Page 46
43
نکلنے پر مجبور ہو گئے اور وہ اپنا مال و اسباب اور اپنے گھر بار چھوڑ چھاڑ کر اپنی جان بچانے
کے لئے مکہ سے بھاگ گئے.جو غریب، بوڑھے، عورتیں اور بچے پیچھے رہ گئے جو بھاگنے کی طاقت نہیں رکھتے
تھے ان کے بڑھاپے اور ان کی بے کسی اور ان کی عورت ذات ہونے پر بھی ان کو رحم نہ آیا
اور ان پر ظلم و تعدی کا ہاتھ دراز کیا.چنانچہ وہ خدا کے آگے نہایت عجز وانکسار سے زاری
کرتے تھے اور چیختے تھے اور گڑ گڑاتے ہوئے کہتے تھے:.رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَّنَا
مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا (النِّسَاء: 76)
اے ہمارے پروردگار! ہم کو اس بستی یعنی مکہ سے کہیں نجات دے جہاں کے رہنے
والے ہم پر ظلم کر رہے ہیں اور خود ہی اپنی طرف سے کسی کو ہمارا حامی بنا اور خود ہی اپنی
طرف سے کسی کو ہمارا مددگار بنا.جو لوگ عمائد مکہ کے ظلم وستم سے رستگاری حاصل کرنے کے لئے گھر بار چھوڑ کر
بھاگ گئے تھے ان کا پیچھا بھی سردارانِ مکہ نے نہ چھوڑا اور چاہا کہ تلوار سے ان کو صفحہ ہستی
سے مٹادیں یا وہ مجبور ہو کر اپنی جان بچانے کے لئے اپنے نئے مذہب سے تائب ہو کر
واپس اپنے آبائی مذہب میں داخل ہو جاویں.چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:.وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ
إنِ اسْتَطَاعُوا (البقرة: 218)
اور یہ کفار سدا تم سے لڑتے ہی رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان سے ہو سکے تو تم کو
تمہارے دین سے واپس اپنے مذہب میں پھیر لیں.غرض تمام مذہبی تاریخ کو دیکھو تمہیں ایک ہی نظارہ نظر آئے گا کہ حق کے متبع کبھی
کسی کو مذہبی عقائد کی وجہ سے دکھ دیتے ہوئے نہیں دیکھے جائیں گے.لیکن ہر زمانہ میں ہم
Page 47
44
دیکھتے ہیں کہ حق کے دشمن ہمیشہ خدا کے راستبازوں کو دکھ دیتے ہیں اور ہمیشہ ان کی یہی
کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنی قوت و بازو کے زور سے راستبازوں کو یا تو فنا کر دیں یا ان کو مجبور
کریں کہ وہ حق سے توبہ کریں.کوئی ایک مثال بھی تم ایسی پیش نہیں کر سکتے جبکہ
راستبازوں کی جماعت نے دین کے معاملہ میں کسی پر جبر کیا ہو.پس مذہبی خیالات کی وجہ سے کسی کو دکھ دینا اور اس کو مجبور کرنا کہ وہ فلاں قسم کے
خیالات قبول کرے خدا تعالیٰ کے نزدیک ایک ظلم ہے اور جو بھی اس فعل کا مرتکب ہو
وہ خدا تعالیٰ کے نزدیک ظالم اور جبار ہے اور خدا تعالیٰ کے آگے اپنے فعل کا جواب دہ ہے
خواہ وہ ریاست کابل کا امیر ہو یا ملک مصر کا فرعون ، خواہ وہ لاہور کا ظفر علی خاں ہو یا وادی
مکہ کا ابوالحکم.مرتدین کے سوال
کا فیصلہ منافقین کی مثال سے
یہ ظاہر ہے کہ جو شخص قتل کے خوف سے اسلام نہیں چھوڑے گا یا قتل کے ڈر سے
ارتداد کے بعد پھر اسلام قبول کرے گا ایسا شخص دل سے مسلمان نہیں ہوگا بلکہ اس کا دل کا فر
ہوگا اور صرف زبان سے اسلام کا اقرار کرے گا.ایسا شخص اسلام کی اصطلاح میں منافق
کہلائے گا.اس لئے منافق کے متعلق قرآن شریف کی تعلیم پر غور کرنے سے ارتداد
کا سوال بھی حل ہو سکتا ہے.اگر قرآن شریف نفاق کی اجازت دیتا ہے اور مسلمانوں کی
جماعت میں منافقوں کے وجود کو استحسان کی نظر سے دیکھتا ہے اور ان سے ویسا ہی سلوک
روا رکھتا ہے جیسا کہ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ تو اس صورت میں بے شک ماننا پڑے گا
کر قتل مرتد جائز ہے.کیونکہ قتل مرتد کی صورت میں جو قباحتیں نظر آتی ہیں اور جو لازمی نتیجہ
اس سے پیدا ہوتا ہے یعنی نفاق اور مسلمانوں کی جماعت میں منافقین کے گروہ کا شامل
ہو جانا ان کے متعلق خیال کیا جا سکتا ہے کہ یہ ایسی باتیں نہیں جو خدا تعالیٰ کو نا پسند ہوں بلکہ
Page 48
45
قرآن شریف اجازت دیتا ہے اور ان امور کو استحسان اور پسندیدگی کی نظر سے دیکھتا ہے
پس اس صورت میں قتل کی سزا مقرر کر کے لوگوں کو ارتداد سے روکنے سے کوئی حرج نہیں
بلکہ یہ بہت ہی اچھی بات ہے لیکن اگر معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے اور خدا تعالیٰ نفاق کی
اجازت نہیں دیتا بلکہ نفاق کو کفر سے بھی بدتر قرار دیتا ہے اور ان سے وہ برتاؤ نہیں کرتا جو
دوسرے مسلمانوں سے کیا جاتا ہے اور اس بات کو پسند کرتا ہے کہ مسلمانوں کی جماعت
ایسے لوگوں کے وجود سے پاک رہے اور اللہ تعالیٰ ضرور خود ایسے ذریعے پیدا کرتا ہے کہ
اسلام کا وجود نفاق کی خبث سے پاک رہے.تو اس سے لازمی طور پر نتیجہ نکلتا ہے کہ مرتد کو
محض ارتداد کی سزا میں قتل کرنا اسلام کی رو سے ناجائز ہے کیونکہ اس سے نفاق پیدا ہوتا ہے
اور اسلام کا خدا چاہتا ہے کہ مسلمانوں کی جماعت منافقین کے خبث سے بکلی پاک رہے.پس آؤ ہم اب قرآن شریف کی طرف رجوع کریں اور دیکھیں کہ اسلام میں
منافقین کی کیا حیثیت ہے.قرآن شریف میں ہمیں منافقین کے بارے میں مندرجہ ذیل
قرآنی آیات اور اسی رنگ کی دوسری آیات نظر آتی ہیں.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:.بَشِّرِ الْمُنْفِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا - (النِّسَاء: 139)
اس آیت کا ترجمہ مولوی نذیر احمد صاحب دہلوی نے حسب ذیل الفاظ میں کیا ہے.(اے پیغمبر) منافقوں کو خوشخبری سنا دو کہ ان کو آخرت میں دردناک عذاب ہونا ہے.پھر اسی رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :-
اِنَّ اللهَ جَامِعُ الْمُنْفِقِينَ وَالْكُفِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا - (النِّسَاء: 141)
اللہ تعالیٰ منافقوں اور کافروں سب
کو دوزخ میں جمع کر کے رہے گا.پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صرف یہی نہیں کہ منافقین کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے
گا جو کفار کے ساتھ کیا جائے گا اور ان کو بھی کفار کی طرح دوزخ میں ڈالا جائے گا بلکہ
منافق دوزخ کے سب سے نیچے کے درجے میں ہوں گے.یعنی وہ اشد ترین عذاب
Page 49
46
میں مبتلا ہوں گے اور اکثر کفار سے بھی زیادہ ان کو عذاب دیا جائے گا.چنانچہ اللہ تعالیٰ
فرماتا ہے:.إِنَّ الْمُنْفِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ (النِّسَاء: 146)
66
اس میں شک نہیں کہ منافق دوزخ کے سب سے نیچے کے درجہ میں ہوں گے.“
اللہ تعالیٰ اس کو بھی پسند نہیں فرما تا کہ منافق مسلمانوں کے ساتھ جہاد میں شریک
ہوں.چنانچہ سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ منافقوں کی نسبت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو
مخاطب کر کے فرماتا ہے:.فَإِن رَّجَعَكَ اللهُ إِلَى طَابِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخَرُوجِ فَقُلْ
أَنْ تَخْرُجُوْا مَعِيَ اَبَدًا وَ لَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا (التوبة:83)
”اے پیغمبر! اگر خدا تم کو (جہاد پر سے) ان منافقوں کے کسی گروہ کی طرف لوٹا کر
لے جائے اور پھر کبھی یہ لوگ جہاد کے لئے نکلنے کی تم سے اجازت چاہیں تو تم ان
سے کہ دینا کہ تم نہ تو کبھی میرے ساتھ جہاد کے لئے نکلو گے اور نہ میرے ساتھ ہوکر
کسی دشمن سے لڑو گے.“
دیتا ہے:.پھر اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعہ منافقین کے گروہ کو اطلاع
قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا أَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمًا
فسِقِينَ وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقْتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُم
كَفَرُوْا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلوةَ إِلَّا وَهُمْ كَسَالَى
وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كُرِهُونَ (التوبة 54،53)
ے پیغمبر! ان لوگوں سے کہو کہ تم خوش دلی سے خرچ کرو یا بے دلی سے تمہاری خیرات
تو کسی طرح قبول ہونی نہیں کیونکہ تم نا فرمان لوگ ہو اور ان کی خیرات کے قبول ہونے کی
Page 50
47
اور کوئی وجہ مانع نہیں ہوئی ،مگر یہی کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی اور نماز کو
آتے ہیں تو سخت سنتی کی حالت میں اور راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں انتہائی بددلی سے.“
پھر اللہ تعالیٰ منافقین کے متعلق اپنے غضب کا اظہار اس طرح کرتا ہے:.سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ
اللهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفُسِقِينَ (المنافقون:7)
ان لوگوں کے لئے تم دعائے مغفرت کر دیا نہ کرو ان کے حق میں دونوں باتیں یکساں
ہیں.خدا تو ان کے گناہ معاف کرنے والا ہے ہی نہیں.بے شک خدا نا فرمان لوگوں کو
ہدایت نہیں دیا کرتا.پھر اللہ تعالیٰ اسی پر اکتفا نہیں کرتا بلکہ حکم دیتا ہے:.وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَّاتَ اَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ
كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَسِقُوْنَ (التوبة: 84)
(اے پیغمبر!) اگر ان میں سے کوئی مرجائے تو تم ہرگز ان کے جنازہ پر نماز نہ پڑھنا
اور نہ ان کی قبر پر جا کر کھڑے ہونا کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر
66
کیا اور سرکشی کی حالت میں مرگئے.“
پھر اللہ تعالیٰ ہر سال ایک یا دو مرتبہ منافقوں کے لئے ایسے سامان پیدا کرتا جن
سے ان کا نفاق ظاہر ہوجاتا اور اللہ تعالیٰ کی اس سے یہ غرض تھی کہ ان کا نفاق ظاہر ہوکر یہ
لوگ مسلمانوں سے ممتاز ہو جاویں اور جب ان کا نفاق کھل جائے گا اور مومنوں پر ظاہر
ہو جائے گا کہ فلاں فلاں شخص منافق ہے تو وہ ہوشیار ہو جائیں گے اور ان کو مومنین کی
جماعت میں شامل سمجھ کر دھوکہ نہیں کھائیں گے اور اس طرح عملی طور پر ان کو اللہ تعالیٰ
مسلمانوں کی جماعت سے خارج کرتا رہتا اور مومنین کے گروہ کو ان کے خبث سے پاک
کرتا رہتا.چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماماتا ہے:.
Page 51
48
اَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ
لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ (التوبة: 126)
کیا یہ لوگ اتنی بات بھی نہیں دیکھتے کہ وہ ہر سال ایک بار یا دو بار آزمائش کی آگ
میں ڈالے جاتے ہیں تا کھرے اور کھوٹے میں تمیز ہو جائے.اس پر بھی نہ تو تو بہ ہی
کرتے ہیں اور نہ نصیحت ہی پکڑتے ہیں.“
اس آیت کریمہ سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تھا کہ منافق اور مومن
ملے جلے رہتے اس لئے وہ ایسے سامان پیدا کر دیتا کہ منافقین کا نفاق ظاہر ہو جاتا اور اس
طرح وہ عملی طور پر مسلمانوں کی خالص جماعت سے الگ ہو جاتے اور مسلمان ان کے
میل جول کے بداثر سے محفوظ ہو جاتے.پس قرآن شریف میں منافقین کا ذکر کثرت کے ساتھ موجود ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ
کے غضب کا مورد ظاہر کیا گیا ہے اور غالبا کفار کی برائی بھی ایسے زور سے بیان نہیں کی گئی
جیسی کہ منافقین کی برائی بیان کی گئی ہے.ان آیات کریمہ کی موجودگی میں کوئی عظمند اس
بات
کو تسلیم نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا حکم دے جس کے نتیجہ میں منافقین لوگ اسلام
میں داخل ہوں.اللہ تعالیٰ تو منافقوں کو مسلمانوں میں سے خارج کرتا ہے تا مسلمانوں کی
جماعت ان کے بداثر سے آلودہ نہ ہو اور وہ ایسے خبیث لوگوں سے پاک اور صاف رہے
اور وہ ایسے حکم دیتا ہے جن کے ذریعہ منافق ،مسلمانوں سے الگ ہو جاویں اور وہ ان میں
مل جل کر نہ رہ سکیں.لیکن ہمیں بتایا یہ جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے ایک ایسا حکم دے رکھا ہے
جس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ لوگ اپنی جان کے خوف سے باوجود بے ایمان ہونے کے
مسلمانوں میں ملے جلے رہیں.ان کے دل میں کفر ہو مگر وہ یہ ظاہر کرتے رہیں کہ ہم
مسلمان ہیں اور اس طرح مسلمانوں میں منافقوں کا گروہ ہمیشہ قائم رہے.قرآن شریف
تو ایسے لوگوں کو دھکے دے دے کر مسلمانوں کی جماعت میں سے باہر نکالتا ہے اور
Page 52
49
مسلمانوں کو ایسے خبیث لوگوں سے پاک اور صاف رکھنا چاہتا ہے.مگر قتل مرتد کے حامی
چاہتے ہیں کہ اسلام ایسے گند سے کبھی پاک نہ ہو اور منافقوں کا ناپاک اور خبیث گروہ ضرور
مسلمانوں میں ہر وقت موجود رہنا چاہئیے اور اگر کبھی کوئی فرد اس گروہ کا مسلمانوں کی
جماعت سے الگ ہونا چاہے تو اس کو قتل کا خوف دے کر جبر سے دوبارہ مسلمانوں کی
جماعت میں داخل کرنا چاہئیے تا یہ گندضرور مسلمانوں میں موجودرہے.پس دیکھو قرآن شریف کی تعلیم میں اور ان لوگوں کے خیالات میں کس قدر بعد اور
ڈوری ہے.قرآن شریف کہتا ہے ان لوگوں کو نکالو.مگر یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو بجائے
باہر نکالنے کے پھر لوٹا کر مسلمانوں میں داخل کریں.ہیں تفاوت راہ از کجا است تا به کجا.منافقین کی مثال قتل مرتد کے سوال کو ایک اور پہلو سے بھی حل کر دیتی ہے.قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ منافقین کو بھی مرتد ہی قرار دیتا ہے.چنانچہ فرماتا ہے:.يَحْلِفُوْنَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوْا كَلِمَةَ الْكُفْرِ
وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ (التوبة: 74)
یہ (منافق) اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم نے تو یہ ( بیجا ) بات نہیں کہی حالانکہ
ضرور انہوں نے کفر کا کلمہ کہا اور اسلام لائے پیچھے کافر ہوئے.“
پھر منافقین کی نسبت فرماتا ہے:.لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيْمَانِكُمْ (التوبة: 66)
باتیں نہ بناؤ حق تو یہ ہے کہ تم ایمان لائے پیچھے کا فر ہو گئے.“
پھر سورۃ منافقون میں اللہ تعالیٰ منافقوں کا ذکر مندرجہ ذیل الفاظ میں کرتا ہے:.اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ
مَا كَانُوا يَعْمَلُوْنَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ أَمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوا فَطِيعَ عَلَى
قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ (المنافقون: 4.3)
Page 53
50
ان لوگوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے.لوگوں کو راہ خدا سے روکتے ہیں.نہایت
ہی برے کام ہیں جو یہ لوگ کر رہے ہیں.اس لئے کہ یہ لوگ پہلے ایمان لائے پھر اسلام
سے پھر گئے یہاں تک کہ ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی تو اب یہ حق بات
کو سمجھتے ہی نہیں.“
پھر منافقین کی نسبت اللہ تعالیٰ یہی نہیں فرما تا کہ یہ لوگ ایمان اور اسلام لانے کے
بعد پھر کافر ہو گئے بلکہ ان کی نسبت خودارتداد کا لفظ بھی استعمال فرماتا ہے.چنانچہ آتا ہے:.إِنَّ الَّذِيْنَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَنُ
سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِيْنَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللهُ
ستطيعكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ (محمد: 27،26)
" بے شک جن لوگوں کو دین کا رستہ صاف طور پر معلوم ہوا اور پھر بھی وہ اپنے الٹے
پاؤں پھر گئے شیطان نے ان کو مبتے دیئے اور ان کی آرزوؤں کی رسیاں دراز کردی
ہیں اور یہ ان لوگوں کا ارتداد اس سبب سے ہے کہ جولوگ ( قرآن کو ) جو خدا نے اُتارا
نا پسند کرتے ہیں ( مثلاً یہود ) یہ منافق ان سے کہا کرتے ہیں کہ بعض باتوں میں ہم
تمہاری صلاح پر چلیں گے اور اللہ ان کی سرگوشیوں کو خوب جانتا ہے.“
غرض منافقین کی نسبت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسلام لانے کے بعد کفر اختیار کرتے
ہیں اور ارتداد کے مرتکب ہوتے ہیں اور جن کو اللہ تعالیٰ مرتد قرار دے ان کے ارتداد میں
کیا شک ہوسکتا ہے.اب اگر یہ بات درست ہے کہ اسلام لانے کے بعد کفر اختیار کرنے
والوں اور ارتداد کر نے والوں کی سزا اسلام میں قتل مقرر کی گئی ہے تو ضروری ہے کہ منافقین
کی سزا بھی قتل ہی ہو.پس اگر یہ ثابت ہو جائے کہ منافقین کی سزا اسلام میں قتل مقرر کی گئی
ہے تو ہم اس بات کو بڑی خوشی سے قبول کر لیں گے کہ واقعی مرتد کی سزا قتل ہے.لیکن اگر
برعکس اس کے یہ ثابت ہو کہ منافقین کی نسبت قرآن شریف قتل کا حکم نہیں دیتا اور جن لوگوں
کا نفاق سب پر واضح ہو چکا تھا اور جن کے نفاق کے متعلق خدا نے گواہی دے دی تھی ان کو
Page 54
51
قتل کی سز انہیں دی گئی تو ہم کو مانا پڑے گا کہ اسلام میں ارتداد کی سزا قتل نہیں ہے.اس امر کے فیصلہ کے لئے جب ہم قرآن شریف کی طرف رجوع کرتے ہیں تو
صاف نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی یہ حکم نہیں دیا کہ منافقین کو قتل کی سزا دی
جائے.برخلاف اس کے قرآن شریف کی آیات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کسی کو اجازت نہ
تھی کہ ان پر قتل کے لئے ہاتھ اٹھائے بلکہ وہ اپنی طبعی موت تک زندہ رہنے دیئے جاتے.چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:.وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَّاتَ اَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ
كَفَرُوا بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ وَمَاتُوْا وَهُمْ فَسِقُوْنَ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ
وَاَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ
أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كُفِرُونَ (التوبة: 85،84)
" (اے پیغمبر) ان میں سے اگر کوئی مرجائے تو اس پر نماز جنازہ نہ پڑھا کر اور نہ اس کی قبر
پر دعا کے لئے کھڑا ہوا کر.کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا اور ایسی حالت
میں مرے ہیں جبکہ وہ اطاعت سے خارج ہورہے تھے.اور ان کے مال اور ان کی اولاد تجھے
تعجب میں نہ ڈالیں.اللہ صرف یہ چاہتا ہے کہ ان مالوں اور اولادوں کے ذریعہ سے ان کو اس
دنیا میں عذاب دے اور یہ کہ ان کی جانیں ایسے وقت میں نکلیں کہ وہ منکر ہی ہوں.“
ان آیات سے ظاہر ہے کہ منافقین کے لئے جن کو اللہ تعالیٰ مرتد قرار دیتا ہے قتل کی
سزا نہ تھی کیونکہ اگر ان کی نسبت یہ حکم ہوتا کہ چونکہ انہوں نے اسلام کے بعد کفر اختیار کیا
ہے اس لئے ان
کو قتل کر دو تو پھر یہ کہنے کی ضرورت نہ تھی کہ اگر ان میں سے کوئی مرجائے تو
اس کا جنازہ نہ پڑھنا.نیز ان آیات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ارتداد کے بعد بظاہر
لوگوں کی نظر میں وہ خوشحالی کی زندگی بسر کرتے تھے اور ان کے پاس بہت سا مال و دولت
اور بہت سی اولا د ہوتی تھی.
Page 55
52
اس سے ظاہر ہے کہ باوجود ارتداد کے وہ اپنے حال پر چھوڑ دیئے جاتے اور
لوگوں کی نظر میں مزے کی زندگی بسر کرتے یہاں تک کہ مسلمان بھی تعجب کرتے کہ یہ
دنیاوی برکت ان کے پاس کیوں ہے.نیز اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ
فَقُل لَّن تَخْرُجُوْا مَعِيَ أَبَدًا وَ لَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا (التوبة: 83)
' (اے پیغمبر) تو ان سے کہہ دے کہ تم کو کبھی بھی میرے ساتھ جنگ پر جانے کی
اجازت نہیں ہوگی اور کبھی بھی تم میرے ہمراہ ہو کر دشمن سے جنگ نہیں کرو گے.“
ظاہر کرتا ہے کہ ان مرتدین کے لئے قتل کا حکم نہیں تھا کیونکہ اگر ان کے لئے قتل کی سزا مقرر
ہوتی تو پھر یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ آئندہ نہ تو تم کبھی میرے ساتھ جہاد کے لئے نکلو
گے اور نہ میرے ساتھ ہو کر کسی دشمن سے لڑو گے.اسی طرح اگر ان مرتدین کے لئے قتل کی
سزا مقررتھی تو پھر یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی.قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا أَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنتُم
إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَسِقِينَ (التوبة : 53)
(اے پیغمبر) تو اُن سے کہہ دے کہ خواہ خوشی سے خرچ کرو خواہ نا خوشی سے، تم سے کسی
صورت میں تمہارا صدقہ قبول نہ کیا جائے گا کیونکہ تم تو اطاعت سے نکل جانے والی قوم ہو.“
اسی طرح تاریخ سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ منافقین کے لئے قتل کی سزا مقر نہیں تھی
اگر منافقین کی نسبت قتل کی سزا مقرر ہوتی تو اس سزا کا سب سے زیادہ مستحق عبداللہ بن ابی
بن سلول تھا جو مدینے کی منافق پارٹی کا سرغنہ تھا اور جس کا نفاق کسی پر مخفی نہیں تھا.لیکن
باوجود اس کے کہ آپ کی خدمت مبارک میں اس کے قتل کے متعلق کئی مرتبہ تحریک بھی کی
گئی پھر بھی آپ نے اس کے قتل کا حکم نہ دیا.خود عبد اللہ بن ابی کا بیٹا بار بار آ نحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا
إِنَّ وَالِدِي يُؤْذِي اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَذَرْنِي حَتَّى أَقْتُلَهُ
Page 56
53
میرا باپ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول (ﷺ) کو ایذا دیتا ہے آپ مجھے اجازت
66
دیں کہ میں اسے قتل کر دوں.“
مگر آپ نے ہر دفعہ اسے روک دیا پھر اس سے بڑھ کر آپ نے اس رئیس
المنافقین کے ساتھ اس کے مرنے پر یہ سلوک کیا کہ آپ نے اس کے بیٹے کو اپنی قمیص عطا
فرمائی تا کہ وہ اسے یہ قمیص بطور کفن پہنا دے اور پھر خود جا کر مع دیگر صحابہ کے اس کا جنازہ
پڑھا.( ممانعت جنازہ کا حکم بعد میں نازل ہوا)
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اشد ترین منافق کے ساتھ جو برتاؤ کیا وہ اس
بات کا کافی ثبوت ہے کہ اسلام میں منافقین کے لئے قتل کی سزا مقر نہیں ہے.غرض جیسا کہ قرآن شریف سے ظاہر ہوتا ہے کہ منافقین کے لئے اسلام قتل کی سزا
مقرر نہیں کرتا اور تاریخ سے ثابت ہے کہ منافقین کو قتل کی سزا نہیں دی جاتی تھی حالانکہ
قرآن شریف منافقین کو بھی مرتد قرار دیتا ہے اس لئے ثابت ہوتا ہے کہ مرتدین کے لئے
اسلام میں
قتل کی سزا نہیں ہے.ممکن ہے کہ کوئی صاحب یہ سوال کریں کہ اگر منافقین کے لئے قتل کا حکم نہیں تو اس
آیت شریف کے کیا معنے ہیں.يَايُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنْفِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ
وَمَاوِيهُمْ جَهَنَّمُ وَبِسَ الْمَصِيرُ (التوبة : 73) :
کہ اے نبی ! کفار اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان پر سختی سے حملہ کرو.ان
کا ٹھکانا جہنم
ہے اور وہ رہنے کے لحاظ سے بہت بُری جگہ ہے.“
اس آیت کریمہ کی تفسیر کے لئے میرے خیال میں فتح البیان کی مندرجہ ذیل
عبارت کافی ہے.وقال الطبرى أولى الاقوال الى قول ابن مسعود لان الجهاد عبارة
Page 57
54
عن بذل الجهد و قد دلّت الآية على وجوب جهاد المنافقين وليس
في الآية ذكر كيفية ذلك الجهاد فلا بد من دليل اخر وقد دلت
الدلائل المنفصلة انّ الجهاد مع الكفّار انّما يكون بالسيف ومع
المنافقين باظهار الحجّة عليهم تارة وبترك الرفق بهم تارة
وبالانتهار تارة و هذا هو قول ابن مسعود.(فتح البیان جلد 4 صفحہ 134)
طبری نے کہا ہے کہ سب اقوال سے میرے نزدیک بہترین قول ابن مسعود کا ہے کیونکہ
جہاد کے معنے ہیں کوشش کرنا.اس آیت کریمہ سے یہ تو ظاہر ہوتا ہے کہ منافقین کے
ساتھ جہاد کرنا واجب ہے لیکن اس آیت میں اس جہاد کی کیفیت بیان نہیں کی گئی.پس
ضروری ہے کہ اس کے لئے کوئی اور دلیل ہو اور کھلے کھلے دلائل سے یہ امر ظا ہر ہوتا ہے
کہ کفار کے ساتھ جہاد تو تلوار کے ساتھ ہوتا ہے اور منافقین کے ساتھ یہ ہے کہ کبھی تو
ان پر اتمام حجت کی جائے اور کبھی نرمی کا سلوک ان کے ساتھ ترک کیا جائے اور کبھی
ان کو زجر کی جائے اور یہی ابن مسعود کا قول ہے.یہاں مولوی نذیر احمد صاحب دہلوی کا ترجمہ اور نوٹ نقل کرنا بھی خالی از فائدہ نہ
ہوگا.مولوی نذیر احمد صاحب اس آیت کریمہ کا ترجمہ حسب ذیل الفاظ میں کرتے ہیں.اے پیغمبر! کافروں کے ساتھ (ہتھیار سے ) اور منافقوں کے ساتھ ( زبان سے )
جہاد کرو اور ان پر سختی کرو کہ (یہ اس سختی کے مستحق ہیں ) اور (آخر کار ) ان کا ٹھکانا دوزخ
ہے اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے.“
اس ترجمہ پر حسب ذیل نوٹ لکھتے ہیں.ہتھیار اور زبان کی قید ہم نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے برتاؤ سے کی ہے کہ
منافقوں پر
کبھی کافروں کا سا جہاد نہیں ہوا.“
Page 58
55
کیا قرآن کریم مقتل مرتد کے سوال پر ساکت ہے؟
قتل مرتد کے حامی قرآن
کریم میں اپنے دعوئی کی کوئی تائید نہ پا کر بلکہ قرآن شریف
کی تعلیم کو اپنے خیال کے بالکل الٹ دیکھ کر اپنے آپ کو بچانے کی اس طرح بے سود کوشش
کرتے ہیں کہ قرآن شریف اس مسئلہ کے متعلق ساکت ہے.مگر یہ حیلہ ان کے لئے کوئی
بچاؤ کا ذریعہ نہیں ہو سکتا.ان کے اس قول کے دوسری لفظوں میں یہ معنے ہیں کہ جب تک
ہم قرآن شریف میں ان کو یہ لکھا ہوا نہ دکھا دیں کہ مرتد کو قتل مت کرو ان کی تسلی نہیں
ہوسکتی.قرآن شریف ایک حکیم کتاب ہے وہ ہر ایک لغو کلام سے پاک ہے.جب قرآن
شریف کی تعلیم ہی اس امر کے مخالف پڑی ہوئی ہے کہ کسی کو صرف مذہب کی تبدیلی پر قتل کیا
جائے وہ بآواز بلند کہہ رہی ہے.فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْ مِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرُ (الكهف: 30)
کہ جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے انکار کر دے.وہ اس امر کا بار بار اعلان کر رہی ہے.مَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا
(بنی اسراءیل : 16)
جو ہدایت کو قبول کرے گا اس کا ہدایت پانا اسی کی ذات کے فائدہ کے لئے ہے اور جو
اس ہدایت کو ر ڈ کر کے گمراہ ہو گا اس کا گمراہ ہونا اسی کے نفس کے خلاف پڑے گا.اور جب وہ پکار پکار کر کہ رہی ہے
مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلْغُ (المائدة: 100)
رسول پر صرف بات کا پہنچانا واجب ہے.
Page 59
56
اور جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
وَمَا اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكيل (الانعام: 108)
(اے پیغمبر ) تو ان پر نگران نہیں ہے.اور جب قرآن شریف نے یہ امر بطور قاعدہ کلیہ کے بیان فرما دیا ہے
لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ (البقرة: 257)
کہ دین کے معاملہ میں
کسی قسم کا جبر جائز نہیں.تو ایسی کھلی کھلی تعلیم کے بعد اس امر کی کوئی ضرورت باقی نہیں تھی کہ مسلمانوں
کو یہ بھی کہا جاتا
کہ جو شخص تم میں سے مرتد ہو جائے اسے قتل نہیں کرنا چاہئے.قرآن شریف کی تعلیم کے
ہوتے ہوئے جب مرتد کے قتل کا سوال ہی پیدا نہیں ہوسکتا تھا پھر اس کی تردید ہی کیوں کی
جاتی.ایسے حالات کے ماتحت یہ کہنا کہ خبردار! مرتد کو ہر گز قتل نہ کرنا ایک لغو کام تھا اور
قرآن جیسی حکیم کتاب کی شان کے بالکل منافی تھا.قرآن شریف ایسی لغو کلام کا مرتکب
نہیں ہوسکتا تھا.علاوہ ازیں قرآن شریف کی دو آیات جن میں ارتداد کا ذکر ہے خود صاف طور پر بتا
رہی ہیں کہ مرتد کے لئے قتل کا حکم نہیں، مثلاً اللہ تعالیٰ یہود کی ایک سازش کا ذکر کرتے
ہوئے فرماتا ہے:.وَقَالَتْ ظَابِفَةً مِنْ أَهْلِ الْكِتَبِ امِنُوْا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ
امَنُوْا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا أُخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (ال عمران: 73)
اہل کتاب میں سے ایک گروہ (اپنے لوگوں کو سمجھاتا ہے کہ مسلمانوں پر جو کتاب
نازل ہوئی ہے اول روز اس پر ایمان لاؤ اور آخر روز اس سے انکار کر دیا کرو شایداس
تدبیر سے ) مسلمان (اس نئے دین سے ) پھر جائیں.“
اس کے جواب میں حامیان قتل مرتد فرماتے ہیں.یہ صرف یہود کی ایک تجویز تھی
Page 60
57
جسے عمل میں نہیں لایا گیا اس لئے اس آیت سے استدلال نہیں ہوسکتا کہ مرتد کو قتل نہیں کیا
جاتا تھا.مگر ان کی یہ جرح بالکل غلط ہے ہم ایک لمحہ کے لئے فرض کر لیتے ہیں کہ یہود کی یہ
صرف ایک تجویز ہی تھی اور اس پر کبھی عمل نہیں کیا گیا پھر بھی یہ آیت اس امر کا ایک قطعی
ثبوت ہے کہ مرتدین کو قتل نہیں کیا جاتا تھا کیونکہ اگر مرتد کی سزا قتل ہوتی اور مرتدین کو قتل کیا
جاتا تو وہ کبھی ایسی تجویز ہی نہ کر سکتے کیونکہ اس سے انہیں سوائے اپنے آدمیوں کو ہلاکت
میں ڈالنے کے اور کوئی نفع نہیں تھا.پس ان کا ایسی تجویز کرنا خود اس امر کا یقینی ثبوت ہے
که مرتدین کو قتل کی سزا نہیں دی جاتی تھی.یہود کی نسبت یہ امید کرنا کہ وہ کسی ایسی غرض
کے لئے اپنی جان
کو یقینی ہلاکت میں ڈالنے کے لئے تیار تھے بالکل ناممکن ہے.ان کے
متعلق تو قرآن شریف شہادت دیتا ہے:.وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيُوةٍ وَمِنَ الَّذِينَ اشْرَكُوا
يَوَدُّ اَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ (البقرة: 97)
البتہ تم پاؤ گے کہ یہ لوگ زندگی پر سب لوگوں سے کہیں زیادہ حریص ہیں یہاں تک کہ
مشرکین سے بھی (جو قیامت ہی کے قائل نہیں ) ان میں سے ایک ایک چاہتا ہے کہ
اے کاش اس کی عمر ہزار برس کی ہو.“
پھر اس آیت کریمہ میں ایک اور جملہ بھی ہے جو اس بات کا یقینی ثبوت ہے کہ
مرتدین کی سزا قتل نہیں تھی اور وہ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ہے.اس میں ان کی سازش کی غرض
بتائی گئی ہے یعنی ایسی تجویز انہوں نے کیوں کی ان کی غرض کیا تھی ؟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ یہ
تجویز انہوں نے اس لئے کی تھی کہ ان کے ارتداد کو دیکھ کر دوسرے مسلمان اسلام کے
متعلق شک میں پڑ جاویں اور اسلام سے ارتداد اختیار کر لیں.لیکن اگر یہ دعویٰ درست
ہے کہ اسلام میں مرتد کے لئے قتل کی سزا مقر رتھی تو ان کی یہ غرض پوری نہیں ہو سکتی تھی.جب وہ جانتے تھے کہ ہر ایک مرتد کوقتل کیا جاتا ہے تو انہیں کبھی امید نہیں ہو سکتی تھی کہ ان کی
Page 61
58
دیکھا دیکھی مسلمان بھی ارتداد اختیار کرلیں گے کیونکہ ان کے مرتد ہوتے ہی جب ان
کو قتل
کیا جاتا تو اس نظارہ کو دیکھ کر تو جو لوگ ارتداد کے لئے تیار ہوتے وہ بھی رک جاتے نہ کہ
اور بھی ارتداد پر آمادہ ہو جاتے.پس اس غرض کا متعین کرنا بھی صاف ظاہر کر رہا ہے کہ
مرتدین کے قتل کا کوئی حکم اسلام میں نہیں تھا.علاوہ ازیں روایات سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کوئی معمولی آنی تجویز نہیں تھی جو
سرسری طور پر بعض یہود کے خیال میں آئی اور دل لگی کے طور پر انہوں نے اس کا ذکر کر دیا
بلکہ مختلف تفاسیر میں ایسے لوگوں کے اسماء اور ان کی تعداد بھی مندرج ہے جنہوں نے یہ
مشورہ کیا اور یہ بھی مذکور ہے کہ انہوں نے اس تجویز پر عمل کرنے کا تہیہ بھی کر لیا.میں یہاں
صرف ایک حوالہ نقل کرتا ہوں.بحر المحیط جلد 2 صفحہ 493 پر لکھا ہے
قال الحسن و السدى تواطا اثنا عشر حبرا من يهود خيبروقرى
عرينة وقال بعضهم لبعض ادخلوا في دين محمد اوّل النهار باللسان دون
الاعتقاد واكفروا به في اخر النهار و قولوا إِنَّا نظرنا في كتبنا وشاورنا
علماء نا فوجدنا محمدًا ليس كذلك وظهر لنا كذبه وبطلان دينه
فاذا فعلتم ذلك شك اصحابه فى دينهم و قالوا هم اهل الكتاب
فهم اعلم منا فيرجعون عن دينهم الى دينكم فنزلت.دد یعنی حسن اور سدی بیان کرتے ہیں کہ یہود خیبر اور عرینہ کی بستیوں کے بارہ عالموں
نے اتفاق کیا اور ایک دوسرے کو کہا کہ محمد (ع) کے دین میں اوّل روز میں داخل
ہو جاؤ صرف زبان سے اقرار کرو اور دل سے نہ مانو ، اور آخر روز میں انکار کر دو اور کہو کہ
ہم نے اپنی کتابوں کو غور سے پڑھا ہے اور اپنے علماء سے بھی مشورہ کیا ہے اور ہمیں
معلوم ہوا ہے
کہ محمد(ﷺ) سچے نبی نہیں ہیں اور ان کا کذب اور ان کے دین کا باطل
ہونا ہم پر ظاہر ہو گیا ہے اور جب تم ایسا کرو گے تو محمد (ع) کے ساتھیوں کو اپنے دین
Page 62
59
میں شک پڑ جائے گا اور وہ کہیں گے یہ لوگ اہلِ کتاب ہیں یہ ہم سے زیادہ جانتے
ہیں.اس طرح وہ اپنے دین سے برگشتہ ہو کر تمہارے دین کی طرف آجائیں گے.“
اسی مضمون کی دیگر روایات جن میں ان مشورہ کرنے والوں کے نام بھی دیئے گئے
ہیں تفسیر کی دوسری کتابوں میں بھی پائی جاتی ہیں.مثلاً ملاحظہ ہو فتح البیان جلد 2
صفحہ 60 - درمنثور جلد 2 صفحه 43,42 - نیز خود قرآن شریف میں اس واقعہ کا ذکر کرنا اور
اس کو اہمیت دینا ظاہر کرتا ہے کہ ایسے واقعات ہوتے رہے، ورنہ کیا ضرورت تھی کہ محض
ایک خام خیال کو جس کا کوئی اثر نہیں تھا خواہ مخواہ قرآن مجید میں بیان کیا جاتا.چنانچہ
صاحب بحر المحیط لکھتے ہیں
اما امتثال الا مرممن امربه فمسكوت عن وقوعه و اسباب النزول
تدلّ على وقوعه (بحر المحيط جلد 2 صفحہ 493)
یعنی اگر چہ قرآن شریف میں اس امر کی تصریح نہیں ہے کہ اس تجویز پر عملدرآمد کیا
گیا یا نہیں لیکن اسباب نزول اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ ایسا کیا گیا.علاوہ ازیں قرآن شریف کے دوسرے مقامات سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس تجویز
پر
عمل کیا گیا اور قرآن کریم اس امر کی شہادت دیتا ہے کہ آنحضور پر نور کے وقت میں ایسے
یہودی موجود تھے جو ایسی شرارتیں کرتے تھے.چنانچہ سورۃ مائدہ رکوع 9 میں اللہ تعالیٰ یہود
کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے:.وَإِذَا جَاءُ وَكُمْ قَالُوا أَمَنَا وَقَدْ تَخَلُوا بِالْكُفْرِوَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ
وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ (المائدة:62)
” ( مسلمانو ! ) جب یہ لوگ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے حالانکہ
کفر ہی کو ساتھ لے کر آئے تھے اور کفر ہی کو ساتھ لے کر چلے بھی گئے اور جو بات وہ دل
میں چھپائے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے.“
Page 63
60
زیر آیت اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ امَنُوا...الآية روح المعانى
جلد 2 صفحہ 196 میں لکھا ہے.عن الحسن انّهم طائفة من اهل الكتاب ارادوا تشكيك اصحاب
رسول الله الا الله فكانوا يظهرون الايمان بحضرتهم ثم يقولون قد
عرضت لنا شبهة أخرى فيكفرون ثم يظهرون ثم يقولون قد
عرضت لنا شبهة اخرى فيكفرون ويستمرون على الكفر الى
الموت.و ذلك معنى قوله تعالى - وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَبِ
امِنُوا بِالَّذِى أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا اخِرَهُ لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ.حسن بصری کا قول ہے کہ آیت کریمہ اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا
میں جن لوگوں کا ذکر ہے وہ اہل کتاب کا ایک گروہ تھا جنہوں نے رسول اللہ ﷺ کے
صحابہ کے دل میں اسلام کے متعلق شک ڈالنا چاہا اس لئے وہ ان کے پاس آ کر پہلے
اپنے ایمان کا اظہار کرتے پھر کہتے ہمارے دل میں اور شبہ پیدا ہو گیا ہے.پھر
انکار کرتے ، پھر موت تک اسی انکار پر قائم رہتے اور یہی معنے ہیں اس آیت کے
وَقَالَتْ ظَابِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَبِ امِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِيْنَ
امَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا خِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (ال عمران: ۷۳)
اور اہلِ کتاب میں سے ایک گروہ کہتا ہے کہ مومنوں پر جو کچھ نازل کیا گیا ہے اس پر دن
کے ابتدائی حصہ میں تو ایمان لے آؤ اور اس کے پچھلے حصہ میں اس سے انکار کر دو.شاید اسی ذریعہ سے وہ پھر جائیں.حسن بصری کے متعلق جن کا قول میں اوپر نقل کر چکا ہوں تہذیب التہذیب
جلد 2 صفحہ 465 میں لکھا ہے:.
Page 64
61
قال ايوب مارأت عيناى افقه من الحسن وقال عطاء بن ابی رباح
كان اماما ضخما يقتدي به.“
یعنی ایوب کہتے ہیں کہ میری آنکھوں نے حسن بصری سے کوئی زیادہ فقیہ انسان نہیں دیکھا
اور عطاء بن ابی رباح کہتے ہیں کہ وہ ایک عظیم الشان امام تھا جس کے قول کی پیروی کی
جاتی ہے.اور امام باقر فرماتے ہیں :.ذلك يشبه كلامه كلام الانبياء وقال محمد بن سعد فانّ الحسن
كان جـامـعـا عـالـمـا رفيعًا فقيها ثقة مامونًاعابدًا ناسكاً كثير العلم
فصيحا جميلا وسيمًا.یہ وہ انسان ہے جس کا کلام انبیاء کے کلام سے مشابہ ہوتا ہے اور محمد بن سعد کا قول ہے
که حسن بصری کامل ماہر، عالم، بلند شان، فقیہ، معتبر، اپنی رائے میں محفوظ، عابد،
پر ہیز گار ، بہت علم والا فصیح اللسان اور خوبصورت شکل وسیرت والے تھے.پس ایسے عظیم الشان انسان
کا یہ قول ہے کہ آیت کریمر انَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ
كَفَرُوا ثُمَّ امَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا میں جن لوگوں کا ذکر ہے کہ وہ پہلے ایمان لاتے پھر ارتداد
اختیار کرتے ، پھر ایمان لاتے ، پھر کفر کرتے وہ یہودی تھے جنہوں نے یہ مشورہ کیا تھا کہ
مسلمانوں کو بہکانے کے لئے اور ان کے دل میں اسلام میں شکوک پیدا کرنے کے لئے یہ
طریق اختیار کیا جائے تا جب مسلمان دیکھیں گے کہ اہلِ کتاب جو ان سے زیادہ عالم ہیں
اسلام لا کر پھر اسلام سے پھر جاتے ہیں تو ان کے دل میں شبہ پیدا ہو گا کہ واقعی اسلام سچا
مذہب نہیں ہے تو وہ بھی اسلام سے پھر جائیں گے.پس حضرت حسن بصری جیسے نیک
انسان جو تابعی تھے جن کا سب
علم صحابہ کی بالمشافہ گفتگو پرمبنی تھا اس تاریخی واقعہ کے متعلق
شہادت دیتے ہیں کہ یہود نہ صرف مشورہ کیا کرتے تھے کہ مسلمان ہو کر مرتد ہو جاؤ بلکہ ایسا
Page 65
62
کیا بھی کرتے تھے اور ایسے شخص کی شہادت جن کا علم صحا بہ کے علم سے بلا واسطہ ماخوذ ہے
اور جو جھوٹ کے شبہ سے پاک ہے نظر انداز نہیں کی جاسکتی.غرض قرآن شریف کی آیت کریمہ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَبِ أَمِنُوا
بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا أُخِرَهُ لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ اس بات کا قطعی اور یقینی ثبوت ہے کہ اسلام میں مرتدین کو ارتداد کی سزا
نہیں دی جاتی تھی اور ان کو ارتداد کی وجہ سے قتل نہیں کیا جاتا تھا ورنہ یہود کبھی ایسی
تجویز نہ سوچتے اور نہ اس پر عمل کرتے اور نہ ان کو یہ امید ہوتی کہ ان کی اس تدبیر سے
مسلمان اپنے دین سے پھر جاویں گے.پس اس آیت کریمہ کی موجودگی میں یہ کہنا کہ
قرآن شریف قتل مرتد کے سوال پر ساکت ہے ایک غلط دعویٰ ہے کیونکہ قرآن شریف
بآواز بلند کہ رہا ہے کہ مرتد کی سزا قتل نہیں.قرآن شریف پر ایک سرسری نظر کرنے سے مجھے پندرہ آیات ایسی ملی ہیں جن میں
ارتداد یعنی کفر بعد اسلام کا ذکر ہے لیکن ان میں ایک آیت بھی ایسی نہیں جس میں مرتد کے
لئے قتل کی سزا کا ذکر ہو اور قتل مرتد کے حامی اس امر کو تسلیم کرتے ہیں کہ ارتداد کی آیات میں
اُخروی سزا کا تو ذکر ہے مگر اس دنیا میں قتل کی سزا دئے جانے کا ذکر کہیں نہیں.لیکن وہ یہ کہتے
ہیں کہ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اس دنیا میں ان
کو قتل کی سزا نہیں دی جائے گی اور اس امر
کی تائید میں وہ قرآن شریف کی مندرجہ ذیل آیت پیش کرتے ہیں.وَمَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَلِدًا فِيهَا وَغَضِ
اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (النساء: 94)
اور جو شخص کسی مومن کو دانستہ قتل کر دے تو اس کی سزا جہنم ہے.وہ اس میں دیر تک رہتا
چلا جائے گا اور اللہ اس سے ناراض ہو گا اور اسے اپنی جناب سے دور کر دے گا اور اس
کے لئے بہت بڑا عذاب تیار کرے گا.
Page 66
63
وہ کہتے ہیں اس آیت کریمہ میں ایسے شخص کے لئے جو کسی مومن کو عمد قتل کر دے
صرف اُخروی سزا کا ذکر ہے.پس کیا اس سے یہ نتیجہ نکل سکتا ہے کہ ایسے شخص کو اس کے
جرم کی سزا اس دنیا میں نہیں دی جائے گی اور کیا ایسا آدمی قتل نہیں کیا جائے گا؟
میں یہ کہتا ہوں یہ قیاس مع الفارق ہے.ان کی پیش کردہ آیت کے نزول سے
پہلے صراحۂ قرآن شریف میں ایسے شخص کے قتل کئے جانے کا حکم نازل ہو چکا تھا اور اس
آیت کریمہ کے نزول کے بعد بھی قصاص کا حکم نازل ہو الیکن قتل مرتد کے متعلق قرآن
شریف میں ایک بھی آیت نہیں چنانچہ قتل مرتد کے حامیوں کو یہ کہنا پڑا ہے کہ قرآن شریف
اس سوال کے متعلق ساکت ہے.وَمَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ کی آیت سورۃ نساء میں نازل
ہوئی اس سے پہلے سورۃ بقرہ میں قصاص کا حکم نازل ہو چکا تھا.چنانچہ اللہ تعالیٰ
فرماتا ہے كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ في القتلى (البقرة: 129) تم پر مقتولوں کے
بارہ میں برابر کا بدلہ لینا فرض کیا گیا ہے اور فرماتا ہے وَلَكُم
فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَأُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (البقرة: 180)
اور اسے عقلمندوں
تمہارے لئے بدلہ لینے میں زندگی کا سامان ہے اور یہ حکم اس لئے
ہے تا کہ تم بیچ جاؤ.نیز سورۃ بنی اسراءیل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:.وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا
فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيْهِ سُلْطَنَّا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا
(بنی اسراءیل:34)
اور جس جان کو مارنا اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے اُسے شرعی حق کے سوا قتل نہ کرو.اور جو شخص
مظلوم مارا جائے اس کے وارث کو ہم نے قصاص کا اختیار دیا ہے پس اس کے لئے یہ
ہدایت ہے کہ وہ قاتل کو قتل کرنے میں ہماری مقرر کردہ حد سے آگے نہ بڑھے.اگر وہ
حد کے اندر رہے گا تو یقیناً ہماری مدد اس کے شامل حال ہوگی.
Page 67
64
نیز سورۃ بقرہ : 195 میں فرماتا ہے:.وَالْحُرُمَتُ قِصَاصُ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ
بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ
اور سب ہی عزت والی چیزوں کی ہتک کا بدلہ لیا جاتا ہے اس لئے جو شخص تم پر
زیادتی کرے تم بھی اس سے اس کی زیادتی کا جس قدر کہ اس نے تم پر زیادتی کی
ہو بدلہ لے لو.اور آیت پیش کردہ کے بعد بھی قصاص کی آیت قرآن شریف میں نازل ہوئی.چنانچہ اللہ تعالیٰ سورۃ مائدۃ میں فرماتا ہے.وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ
وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَ بِالسِّنِ وَالْجُرُوحَ قِصَاص (المائدة: 46)
اور ہم نے اس تو رات میں ان پر فرض کیا تھا کہ جان کے بدلہ میں جان اور آنکھ کے
بدلہ میں آنکھ اور ناک کے بدلہ میں ناک اور کان کے بدلہ میں کان اور دانت کے بدلہ
میں دانت اور زخموں کے بدلہ میں زخم برابر کا بدلہ ہیں.پس قاتل متعمد کے متعلق تو قتل مرتد کے حامی صرف ایک آیت ایسی پیش کرتے
ہیں جس میں اُخروی سزا کا ذکر ہے اور قصاص کا ذکر نہیں لیکن اُس ایک آیت کے مقابل
میں کم از کم چار آیتیں موجود ہیں جن میں ایسے قاتل سے قصاص کا صریح حکم موجود ہے.مگر قرآن شریف میں کم از کم پندرہ آیات موجود ہیں جن میں ارتداد کا ذکر تو ہے
لیکن قتل کی سزا کہیں بھی مذکور نہیں.پس حامیان قتل مرتد کا وَمَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا
فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ کی آیت کو بطور نظیر کے پیش کرنا ان کے لئے کچھ بھی مفید نہیں بلکہ اس
سے ان کے خلاف استدلال ہو سکتا ہے کہ اگر مرتد کے لئے بھی قتل کی سزا ہوتی تو جیسے قاتل
کی صورت میں اگر ایک جگہ صرف اُخروی سزا کا ذکر ہے تو کم از کم چار جگہ قصاص کا صریح
Page 68
65
حکم موجود ہے.اسی طرح اگر مرتد کے لئے بھی قتل کی سزا مقرر ہوتی تو جب بار بار قرآن
شریف مرتد کے لئے اُخروی سزا کا ذکر کرتا ہے (جیسے عام کافر کے لئے ) تو کم از کم ایک
مرتبہ ہی اس کے قتل کئے جانے کا ذکر فرما دیتا.پس قرآن شریف کا بار با را خروی سزا کا ذکر
کرنا اور قتل کی سزا کا کہیں بھی ذکر نہ کر نا صاف طور پر ظاہر کرتا ہے کہ مرتد کے لئے خدا تعالیٰ
نے قتل کی سزا مقرر نہیں فرمائی.خصوصاً جب کہ ہم تمام قرآن شریف کو ضمیر کی آزادی کی
آیات سے بھرا ہوا دیکھتے ہیں اور جب کہ علی الا علان اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:.فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنُ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرُ اور لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ
مِنَ الْغَيِّ.کہ جو چاہے مانے اور جو چاہے نہ مانے اور یہ کہ دین کے معاملہ میں کسی قسم کا جبر جائز
نہیں.ہدایت اور گمراہی کا فرق خوب ظاہر ہو چکا ہے.نیز یہ بات بھی نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ ارتداد کی آیات قریباً سب کی سب
مدینہ میں ایسے وقت میں نازل ہوئیں جب کہ اسلامی سلطنت قائم ہو چکی تھی اور قتل کی سزا
کا نفاذ بھی ہو سکتا تھا.پھر کیوں اُخروی سزا پر انحصار رکھا گیا حالانکہ اُخروی سزا کا تو انسان
مشاہدہ نہیں کر سکتا.اس لئے سب سے پہلے وہ سزا بیان کرنی چاہئیے تھی جونزول کے وقت
دی جاسکتی تھی.لیکن میں کہتا ہوں یہ کہنا بھی درست نہیں کہ قرآن شریف کی آیات متعلقہ
ارتد اقتل مرتد کے سوال پر ساکت ہیں.میں او پر لکھ چکا ہوں کہ قرآن شریف میں کم از کم
پندرہ آیات ایسی ہیں جن میں کفر بعد اسلام کا ذکر ہے اور ان میں سے ہر ایک اس امر کی
شہادت دیتی ہے کہ مرتد کے لئے اسلام میں قتل کی سزا نہیں ہے.ان پندرہ آیات
میں سے ایک آیت تو وہ ہے جس کے متعلق میں پہلے بحث کر چکا ہوں یعنی
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَبِ امِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا
وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا أُخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (ال عمران : ۷۳)
Page 69
66
اور جیسا کہ میں ابھی ثابت کر چکا ہوں اس آیت کریمہ سے صاف طور پر
ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام میں قتل کی سزا نہیں دی جاتی تھی اور کفر بعد اسلام کے متعلق چار
آیتیں میں منافقین کی بحث میں لکھ چکا ہوں جن میں اللہ تعالی منافقین کے متعلق شہادت
دیتا ہے کہ انہوں نے اسلام لانے کے بعد کفر اختیار کیا ہے اور ارتداد کا لفظ بھی استعمال
فرماتا ہے لیکن کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے منافقین کو قتل کا حکم نہیں دیا.باقی دس آیات میں جن کو
میں یکے بعد دیگرے پیش کروں گا.پہلی اور دوسری آیت مع آیات متعلقہ
كَيْفَ يَهْدِى اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيْمَانِهِمْ وَ شَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ
حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنْتُ وَاللهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّلِمِينَ أَو لَكَ
جَزَاؤُهُمْ اَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللهِ وَالْمَلَكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ خَلِدِينَ
فِيْهَا ۚ لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ إِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوا
مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ إِنَّ الَّذِينَ
كَفَرُوا بَعْدَ إِيْمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَّنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَيكَ
هُمُ القَانُونَ إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا وَمَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارُ فَلَنْ
يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَى بِهِ أُولَكَ لَهُمْ عَذَابٌ
اليم وَمَا لَهُمْ مِنْ نَّصِرِينَ (ال عمران: 9287)
جولوگ ایمان لانے کے بعد پھر منکر ہو گئے ہوں اور شہادت دے چکے ہوں کہ یہ رسول
سچا ہے اور نیز ان کے پاس دلائل بھی آچکے ہیں انہیں اللہ کس طرح ہدایت پر لائے اور
اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا.یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ اور
فرشتوں کی اور لوگوں کی سب ہی کی لعنت ہو.وہ اس لعنت میں رہیں گے.نہ تو ان پر سے
Page 70
67
عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں ڈھیل دی جائے گی.سوائے ان لوگوں کے جواس
کے بعد توبہ کر لیں اور اصلاح کرلیں اور اللہ یقیناً بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا
ہے.جو لوگ ایمان لانے کے بعد منکر ہو گئے ہوں پھر وہ کفر میں اور بھی بڑھ گئے ہوں
ان کی تو بہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی اور یہی لوگ گمراہ ہیں.جولوگ منکر ہو گئے ہوں اور
کفر ہی کی حالت میں مر گئے ہوں ان میں سے کسی سے زمین بھر سونا بھی جسے وہ فدیہ
کے طور پر پیش کریں ہر گز قبول نہیں کیا جائے گا.ان لوگوں کے لئے دردناک عذاب
مقدر ہے اور ان کا کوئی بھی مددگار نہ ہوگا.مندرجہ بالا اقتباس میں دو آیات ایسی ہیں جن میں کفر بعد ایمان کا ذکر ہے اور ان
دونوں آیات سے یہ امر صاف طور پر ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام میں ارتداد کی سزا قتل نہیں ہے.پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ پہلے سچے دل سے اس نبی پر ایمان
لے آئے اور زبان سے اس کی صداقت کا اقرار کیا اور اس طرح اقرار باللسان و تصدیق
بالقلب کے مصداق ٹھہرے مگر پھر کسی نفسانی وجہ سے انکار کر دیا تو ایسے ظالموں کو ہدایت
نہیں مل سکتی لیکن اگر وہ خدا تعالیٰ کی طرف آنا چاہیں تو پھر خدا تعالیٰ ان کے لئے دروازے
کھول دیتا ہے.دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ ارتداد کے بعد کفر میں بڑھتے
جاتے ہیں تو ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں کیونکہ یہ لوگ ایک طرف کفر میں بڑھتے جاتے
ہیں اور دوسری طرف منہ سے تو بہ کرتے ہیں.ان کی ایسی تو بہ فائدہ نہیں دیتی.ان دونوں آیات سے یہ مستنبط ہوتا ہے کہ ارتداد کے بعد مرتد اپنے حال پر
چھوڑ دیا جاتا ہے.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مرتد دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں.ایک وہ جو بعد
میں سچی توبہ کر لیتے ہیں ایسے لوگوں کے لئے اللہ تعالیٰ ہدایت کے دروازے کھول دیتا
ہے.دوسرے وہ جو اپنے کفر میں بڑھے چلے جاتے ہیں اور اگر تو بہ بھی کرتے ہیں تو
Page 71
68
جھوٹی ، ایسے لوگوں کے لئے اللہ تعالیٰ ہدایت روک لیتا ہے اور وہ اپنی گمراہی میں بڑھے
چلے جاتے ہیں.ان آیات کے پڑھنے سے پہلا اثر جو ہر ایک انصاف پسند انسان کے دل
پر پڑتا ہے وہ یہی ہے کہ ارتداد کے بعد مرتدین پر کوئی جبر نہیں ہوتا وہ اپنے حال پر
چھوڑ دیئے جاتے ہیں.جو بعد میں کچی تو بہ کریں تو ان
کی تو بہ اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے اور
جو لوگ کچی تو بہ نہیں کرتے اور اپنے کفر میں ترقی کرتے چلے جاتے ہیں ایسے لوگ ہمیشہ
کے لئے ہدایت سے محروم رہتے ہیں اور گمراہی ہی میں اس دنیا سے گزر جاتے ہیں.پس
ان آیات میں یہ مفہوم ضرور مرکوز ہے کہ مرتد کو قتل کی سزا نہیں دی جاتی تھی بلکہ ان کو
خدا تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل دی جاتی تھی.کچی تو یہ جبر اور قتل کے سوال کو رڈ کرتی ہے
کیونکہ جب مرتد ہوتے ہی مسلمان
تلوار کھینچ کر اس کے گرد ہو جاویں گے کہ تو بہ کرو ورنہ
تمہیں قتل کر دیا جائے گا تو ایسے حال میں اس کی تو به جبر وا کراہ کی تو بہ ہوگی نہ کہ تو به نصوح.اسی طرح مرتد کا اپنے کفر میں ترقی کرتے جانا بھی ظاہر کرتا ہے کہ اس کو خدا تعالیٰ ڈھیل
دیتا ہے اور اسے لمبی مہلت دی جاتی ہے کسی تلوار سے اس کی زندگی کا خاتمہ نہیں کیا جاتا.پس یہ دو نو آیتیں قتل مرتد کے عقیدہ کی تردید کر رہی ہیں.ان آیات پر حامیان
قتل
مرتد نے یہ جرح کی ہے کہ ان کا سیاق و سباق بتلاتا ہے کہ یہاں پر اسلام لا کر مرتد ہونے کا
ذکر نہیں بلکہ یہ کہ اہلِ کتاب حضور سرور کائنات پر ایمان لانے کا عہد و پیمان کرنے کے بعد
آپ کی تشریف آوری پر تمام بینات سے منکر ہو گئے تھے اسی کفر بعد ایمان کا ان آیات میں
ذکر ہے اور لکھتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ ان آیات کا یہ سلسلہ ارتداد پیش کرنا ہی قرآن
(شریف) سے انتہا درجہ کے جہل کا ثبوت ہے.مگر یہ مولوی صاحبان کی خوش فہمی ہے اور
حقیقت یہ ہے کہ سلسلہ ارتداد میں ان آیات کا پیش کرنا قرآن شریف سے انتہا درجہ کے
جہل کا ثبوت نہیں بلکہ ان کے یہ الفاظ خودان پر صادق آتے ہیں.نبی کریم صلی اللہ علیہ
وسلم فرماتے ہیں اوتیت جوامع الکلم ( بخاری ) یعنی جو کلام مجھے دیا گیا ہے اس میں یہ
Page 72
69
خصوصیت ہے کہ تھوڑے لفظوں میں بہت سے معانی ادا کئے گئے ہیں.یہ نہیں کہ قرآن
شریف کی ہر ایک آیت ایک ہی مفہوم تک محدود ہے اور کوئی دوسرا مفہوم اس سے نکالنا غلطی
ہے.ایک آیت کو صریح الفاظ کے ہوتے ہوئے ایک ہی معنی میں مخصوص کرنا صحیح نہیں بلکہ
کئی مفہوم نکل سکتے ہیں بشرطیکہ ایک معنے دوسرے معنوں کے متضاد نہ ہوں.پس آیات زیر بحث میں اگر حامیان
قتل مرتد کے معنے بھی درست مان لئے جائیں
تو اس سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا ہے کہ کفر بعد اسلام کے ظاہری اور اقرب معنے لینا غلطی ہے بلکہ
ان کے پیش کردہ معنوں کے باوجود آیت اپنے ظاہری معنوں میں بھی درست ماننی پڑے
گی اور حامیان
قتل مرتد یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ یہاں ایمان کے کوئی خاص معنے ہیں اس
لئے عام اور معروف معنے لینا جہالت ہے.عام اور معروف معنے لینا جہالت نہیں بلکہ جو
شخص ان پر اعتراض کرتا ہے وہ خود اپنی جہالت کا ثبوت دیتا ہے.افسوس ! کہ معترضین کو تمام مفسرین کے مشہور ومعروف اور مسلم اصول کا بھی علم نہیں
اگر کسی آیت کریمہ کے نزول کا کوئی خاص سبب یا موقع ہو تو وہ آیت اس خاص موقع اور محل
کے لئے مخصوص نہیں سمجھی جاتی بلکہ وہ اپنے الفاظ کے مفہوم کے جائز دائرہ کے اندر پوری
پوری وسعت اور عمومیت رکھتی ہے.چنانچہ مفسرین نے اس کے متعلق جو اصل باندھا ہے
وہ یہ ہے الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب یعنی ہر ایک آیت اپنے الفاظ
کے عام معنوں میں لی جائی گی جس محل پر وہ پہلی دفعہ نازل ہوئی اس محل و موقع میں اس کو
محصور نہیں سمجھا جائے گا.(ملاحظہ ہو قتوی علی البیضاوی جلد اوّل صفحہ 131 ) اسی طرح روح
المعانی جلد 2 صفحہ 294 پر لکھا ہے و سبب النزول لا يصلح مخصصا فان العيرة
كمـا تـقـرر بعموم اللفظ لا بخصوص السبب یعنی کسی آیت کا سبب نزول اس
آیت کی تخصیص نہیں کرتا بلکہ وہ آیت اپنے عام معنوں میں
سمجھی جائے گی اور اس کو اس
Page 73
70
واقعہ کے ساتھ مختص نہیں
سمجھا جاوے گا.جیسا کہ مسلّم ہے.پس اگر حامیان قتل مرتد کا یہ کہنا درست بھی مان لیا جائے کہ یہ آیات ان یہود کے
متعلق ہیں جنہوں نے یہ عہد کیا تھا کہ جب نبی موعود کا ظہور ہوگا تو ہم ان پر ایمان لائیں
گے لیکن آنحضور پر نور کے ظہور قدسی کے وقت وہ منکر ہو گئے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ
یہ آیات عام مرتدین پر چسپاں نہیں ہو سکتیں جو اسلام لانے کے بعد کفر اختیار کریں.علاوہ ازیں خودان آیات کا مضمون اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ یہود کے لئے
مخصوص نہیں بلکہ عام ہیں.ان آیات میں تین گروہوں کا ذکر ہے.اوّل وہ جو ارتداد
اختیار کرنے کے بعد پھر بھی تو بہ کرتے ہیں.دوم وہ جوتو یہ نہیں کرتے بلکہ اپنے کفر میں
ترقی کرتے جاتے ہیں.تیسرے وہ جو ابتداء سے ہی کا فر رہتے ہیں.یہ ایک عام تقسیم ہے
اور کوئی وجہ نہیں کہ اس کو یہود تک محدود کیا جائے.اسی طرح ان آیات سے ماقبل کی آیت
دیکھو:.وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن تُقْبَلَ مِنْهُ ۚ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ
مِنَ الْخُسِرِينَ (آل عمران : 86)
اور جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کو اختیار کرنا چاہے تو وہ یادر کھے کہ وہ اس سے ہرگز
قبول نہیں کیا جائے گا.اور آخرت میں وہ نقصان اُٹھانے والوں میں سے ہوگا.کیا یہ آیت صرف یہود کے لئے مخصوص ہے یا سب پر حاوی ہے.پھر ان آیات
سے مابعد کی آیت پڑھو :.لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ (ال عمران: 93)
تم کامل نیکی کو ہرگز نہیں پاسکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ اشیاء میں سے خدا کے لئے
خرچ نہ کرو.کیا حامیان قتل مرتد کے نزدیک اس آیت میں صرف یہود ہی مخاطب ہیں؟ جب
Page 74
71
پہلی آیت اور بعد کی آیت اپنے مفہوم میں عام ہیں تو کیا وجہ ہے کہ ان دونوں آیات کی
درمیانی آیات کو باوجود الفاظ کی عمومیت کے صرف یہود کے لئے خاص سمجھا جائے.حامیان قتل مرتد فرماتے ہیں کہ ان آیات کو بہ سلسلہ ارتداد پیش کرنا ہی قرآن
سے انتہا درجہ کے جہل کا ثبوت ہے.( زمیندار 20 مارچ 1945ء کالم 2 صفحہ 2) ان
صاحبان کی دل چسپی کے لئے میں چند خاص خاص تفاسیر سے کچھ اقتباس ذیل میں درج
کرتا ہوں تا ان بزرگوں کو دیکھ کر حیرت ہو کہ صرف ہم ہی نہیں جنہوں نے بسلسلہ ارتداد
پیش کر کے قرآن شریف سے انتہا درجہ کا جہل کا ثبوت دیا ہے بلکہ وہ جو مسلمانوں میں چوٹی
کے مفسر شمار کئے جاتے ہیں وہ بھی ہماری طرح اسی انتہا درجہ کے جہل میں مبتلا ہیں.پہلا مفسر جس نے ان آیات کو مرتدین پر چسپاں کر کے بقول مولوی ظفر علی خان
صاحب قرآن شریف سے انتہا درجہ کے جہل کا ثبوت دیا ہے ، روح البیان کا مصنف ہے.وہ لکھتا ہے:.فان قيل ظاهر الأية يقتضي ان من كفر بعد اسلامه لا يهديه الله ومن
كان ظالمًا لا يهديه الله وقدر اينا كثيرا من المرتدين اسلموا
و هداهم وكثير من الظالمين تابوا عن الظلم فالجواب ان معناه لا
يهديهم ما داموا مقيمين على الرغبة فى الكفرو التِّبَابُ عليه ولا
يقبلون على الاسلام واما اذا تحروا اصابة الحق والاهتداء بالادلة
المنصوبة فَحِينَئِذٍ يهديهم الله بخلق الاهتداء فيهم.روح البیان جلد نمبر 1 صفحه 344)
دوسرا مفسر جس نے بقول مولوی ظفر علی خان صاحب ایسے انتہا درجہ کے جہل کا ثبوت
دیا ہے، ابن جریر ہے.وہ اس آیت کے متعلق لکھتے ہیں :.بقول مولوی ظفر علی خان صاحب
Page 75
72
نزلت في اثناعشر رجلا رجعوا عن الاسلام ولحقوا بقريش ثم
كتبوا الى اهلهم هل لنا من توبة فنزلت إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ
ذلك.( ابن جریر جلد 3 صفحہ 242)
تیسرا مفسر جن نے بقول مولوی ظفر علی خان صاحب قرآن شریف سے ایسے انتہا
درجہ کے جہل کا ثبوت ہے، ابن کثیر ہے.وہ لکھتا ہے:.عن عكرمة عن ابن عباس ان قومًا اسلموا ثم ارتدوا افارسلوا الى
قومهم يسألون لهم فذكروا ذلك لرسول الله الله فنزلت هذه
الآية إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيْمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ -
هكذا رواه و اسناده جيد.ابن کثیر بر حاشیہ فتح البیان جلد نمبر 2 صفحہ 249)
چوتھا مفسر جس کو اسی زمرہ میں شامل کرنا چاہئیے ، بحر المحیط کا مصنف ہے.وہ لکھتا
ہے:.او معنى ثُمَّ ازْدَادُوا كُفَرًا تموا على كفرهم وبلغوا الموت به
فيدخل فيه اليهود والمرتدون قاله مجاهد و قال نحوه السدى
وقيل نزلت فيمن مات على الكفر من اصحاب الحارث بن سويد.(بحر المحيط جلد نمبر 2 صفحہ 519)
تیسری آیت
مَنْ كَفَرَ بِاللهِ مِنْ بَعْدِ اِيْمَانِةٍ إِلَّا مَنْ ُأكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَينَ بِالْإِيْمَانِ وَلَكِنْ
مَّنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ
ذلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيُوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى
الْقَوْمَ الْكَفِرِينَ ) (النحل: 107 ،108)
Page 76
73
جو شخص ایمان لائے پیچھے خدا تعالیٰ کے ساتھ کفر کرے سوائے اس کے جو کفر پر مجبور کیا
جائے اور س کا دل ایمان پر مطمئن ہو.لیکن ہاں وہ جو جی کھول کر کفر کرے تو ایسے لوگوں
پر خدا کا غضب اور ان کے لئے سخت عذاب ہے.یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے دنیا کی
زندگی کو آخرت کے مقابلہ میں پسند کیا اور یہ کہ اللہ ان لوگوں کو جو کفر کرتے ہیں ہدایت
نہیں دیا کرتا.“
اس آیت کریمہ میں بھی دوسری آیات کی طرح صرف اُخروی سزا کا ذکر ہے
قتل کی سزا کا کوئی ذکر نہیں.لیکن مولوی ظفر علی خان صاحب اس آیت کریمہ پر یہ جرح
کرتے ہیں کہ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اُخروی وعید کے علاوہ اس دنیا میں کوئی اور
سزا نہ ملنی چاہئیے.اول تو کسی آیت میں بھی قتل کی سزا کا ذکر نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ارتداد
کی سزا قتل نہیں ہے لیکن اگر اس آیت پر غور کیا جائے تو صرف یہی ظاہر نہیں ہوتا کہ اس
میں صرف اُخروی سزا پر انحصار کیا گیا ہے بلکہ یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ارتداد کی سزا قتل نہیں
ہے کیونکہ
(1) قتل کی سزا میں اکراہ لازم آتا ہے اور اس آیت کریمہ میں کنایہ (اور دیگر
آیات میں صراحۃ) (اکراہ فی الدین کو نا جائز قرار دیا گیا ہے اور ایسے لوگوں کو جو تبدیلی
عقائد کی وجہ سے لوگوں کو دکھ دیتے ہیں برا کہا گیا ہے.(2) اس آیت کریمہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ عقائد کا تعلق دل سے ہوتا ہے.پس
اگر ایک انسان
قتل کے خوف سے ظاہر میں ایمان کا اقرار بھی کرے مگر دل سے کافر ہو تو
ایسے اقرار سے مسلمانوں
کو یا خود اس شخص کو کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے؟
(3) ان آیات میں مرتدین پر غضب کی وجہ بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:.ذلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيَوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ
Page 77
74
یعنی یہ غضب اور یہ عذاب اس لیے ہے کہ انہوں نے ورلی زندگی کو آخرت کے مقابل میں
پسند کیا.ان الفاظ سے بھی پایا جاتا ہے کہ ارتداد کی سزا اقتل نہیں تھی.کیونکہ مرتدوں کو اگر فوراً
ارتداد کے بعد قتل کر دیا جاتا تو ذلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ
والی غرض پوری نہیں ہوسکتی تھی.یہ غرض تو اسی صورت میں پوری ہو سکتی تھی کہ ارتداد کے بعد
وہ زندہ رہتے اور ان کے قتل کا حکم نہ ہوتا.چوتھی آیت
إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ امَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كَفَرًا لَّمْ يَكُنِ اللَّهُ
لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا (النساء: 138)
جو لوگ اسلام لائے اور پھر اسلام سے انکار کر دیا پھر اسلام لائے اور پھر انکار کیا،
اور پھر اس کے بعد کفر میں بڑھتے گئے تو خدا نہ تو ان کی مغفرت ہی کرے گا اور نہ ان کو
راہِ راست ہی دکھائے گا.“
اس آیت پر بھی یہی اعتراض کیا گیا ہے کہ اس میں اگر دنیوی سزا کی صراحت
نہیں تو نفی بھی نہیں.میں کہتا ہوں یہی تو معرض بحث ہے کہ باوجود قرآن کریم میں کئی جگہ
مرتدین کا ذکر ہونے کے پھر تمہاری مزعومہ سزا کا کہیں ذکر نہیں.اگر یہ سزا ہوتی تو ضرور کسی
نہ کسی جگہ اس کا اشارہ ہوتا.پس ہماری دلیل یہ ہے کہ ہر جگہ ارتداد کی سزا اُخروی عذاب ہی
فرمانا قتل کی نفی ہے.دوسرے اس آیت میں دو دفعہ ایمان اور دو دفعہ کفر کا ذکر ہے اور پھر اصرار علی الکفر
کا ذکر ہے.اگر ارتداد کی سزا قتل ہوتی تو ایسے نظارہ کا مشاہدہ ناممکن تھا.قتل کی سزا کی
موجودگی میں کسی جماعت یا فرد سے ایسی جرات کا اظہار نہیں ہو سکتا تھا.تیرے ثُمَّ ازْدَدُوا كُفْرًا میں لمبے عرصہ کا مفہوم پایا جاتا ہے.دوتین دن کی مہلت
Page 78
75
میں تو بہ نہ کرنے پر یہ الفاظ چسپاں نہیں ہو سکتے بلکہ یہ ایک لمبا عرصہ چاہتے ہیں.پس اس آیت
کے الفاظ یقینی طور پر ظاہر کرتے ہیں کہ کس کو محض ارتداد کی وجہ سے
قتل نہیں کیا جاتا تھا.چوتھے اس آیت کے متعلق حسن بصری کا یہ قول ہے کہ
انهم طائفة من اهل الكتب ارادوا تشكيك اصحاب رسول الله
صلى الله
علة وكانوا يظهرون الايمان بحضرتهم ثم يقولون قد عرضت لنا
ه
شبهة فيكفرون ثم يظهرون ثم يقولون قد عرضت لناشبهة أخرى
فيكفرون ويستمرون على الكفر الى الموت و ذلك معنى قوله
تعالى: وقالت طائفة من اهل الكتب إلى لعلهم يرجعون.(روح المعانی جلد نمبر 2 صفحہ 196 )
یعنی اس آیت میں جن لوگوں کا ذکر ہے وہ اہل کتاب کی ایک جماعت تھی جنہوں
نے صحابہ کے دل میں اسلام کے متعلق شک ڈالنا چاہا اس لئے ان کے پاس آ کر وہ ظاہر
کرتے کہ ہم بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں.پھر بعد میں کہتے کہ ہمارے
دل میں شبہ پیدا ہو گیا ہے اور ارتداد اختیار کرتے.پھر آ کر ایمان کا اظہار کرتے پھر کہتے کہ
ہمارے دل میں اور شبہ پیدا ہو گیا ہے اور پھر اسلام سے انکار کرتے اور پھر اسی انکار پر قائم
رہتے یہاں تک کہ مرجاتے اور یہی معنی ہیں اس آیت کریمہ کے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا
ہے کہ اہل کتاب کی ایک جماعت نے کہا کہ اوّل روز میں قرآن پر ایمان لاؤ اور آخر روز
میں انکار کر دو تا اس حیلہ سے مسلمان اسلام سے روگردانی کر لیں.پس حضرت حسن بصری
کے اس قول سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ مرتدین کو قتل کی سزا نہیں دی جاتی تھی.پانچویں آیت
وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ
Page 79
76
اِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَمَتْ وَهُوَ
كَافِرُ فَأُولَيْكَ حَطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ **
وَأُولَيكَ أصْحَبُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خُلِدُونَ (البقرة: 218)
اور یہ کفار تم سے برابر لڑتے ہی رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان کا بس چلے تو تم کو
تمہارے دین سے برگشتہ کر دیں اور جو تم میں سے اپنے دین سے برگشتہ ہوگا اور کفر ہی
کی حالت میں مرجائے گا تو ایسے لوگوں کا کیا کرایا دنیا اور آخرت دونوں میں اکارت
گیا اور یہی ہیں دوزخی اور وہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ ہی میں رہیں گے.“
66
اس آیت کریمہ میں بھی کسی دنیوی سزا کا ذکر نہیں اور یہ نہیں کہا گیا کہ مرتد کو قتل
کیا جائے گا.اس آیت کریمہ پر ایک مولوی صاحب جرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں:.اس آیت میں بھی قیمت کا لفظ سزائے قتل کا منافی نہیں.اس لئے کہ اول تو یہ لفظ
موت بالقتل اور موت طبعی دونوں پر یکساں حاوی ہے اور اس کے استعمال سے مقصود یہ
معلوم ہوتا ہے کہ عام مرتدین کے ساتھ ساتھ ان مرتدین کے متعلق بھی صراحت کر دی
جائے جو ارتداد اختیار کرتے ہی ہیئت حاکم اسلام کے دائرہ اثر واقتدار سے باہر نکل
جائیں اور اسلامی حکومت کا محکمہ قضاء ان پر حد جاری نہ کر سکے.اس کے علاوہ یہ آیت
ان مرتدین کی حالت پر بھی منطبق ہوتی ہے جو کسی غیر مسلم حکومت کے ماتحت ہونے
کے باعث شرعی سزائے قتل سے محفوظ رہتے ہیں.“
اس اقتباس میں اس آیت کریمہ کے سزائے قتل کے منافی نہ ہونے کی دو وجوہات
لکھتے ہیں.اوّل یہ کہ اس میں موت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جو قتل اور طبعی موت دونوں
پر حاوی ہے اور یہ مشتر کہ لفظ اس لئے استعمال کیا گیا ہے کہ عام مرتدین کے ساتھ ساتھ ان
مرتدین کے متعلق بھی صراحت کر دی جائے جو اسلامی سلطنت سے بھاگ جانے کے
باعث سزائے قتل سے محفوظ ہو جاتے ہیں.”عام مرتدین سے مولوی صاحب کی مراد وہ
Page 80
77
مرتدین ہیں جن کو قتل کی سزا دی جائے گی.مگر میں مولوی صاحب سے پوچھتا ہوں کہ
بقول آپ کے موت کا لفظ رکھ کر استثنائی صورت کی تو صراحت کر دی گئی مگر عام حکم کی بھی
صراحت ہونی چاہئیے تھی.جس کے ساتھ ساتھ اس استثنائی صورت کی وضاحت کی گئی ہے
وہ کہاں ہے؟ عام مرتدین کے متعلق تو قتل کی سزا تھی اور ایسے احکام کسی قانون کی کتاب
میں ذومعنی الفاظ میں کبھی نہیں دیئے جاتے.اول ضرورت تو عام قاعدہ کی تھی کہ مرتد کوتل
کر دو.اس حکم کی صراحت نہیں کی گئی اور بقول آپ کے استثناء کی صراحت کر دی گئی ہے.مولوی صاحب! یہ استثناء ایسا نہیں تھا.جس کے ذکر کی بھی ضرورت ہوتی.کیونکہ جس کو ذرا
بھی عقل ہو وہ سمجھ سکتا ہے کہ جو شخص ارتداد اختیار کرتے ہی ہیئت حاکم اسلام کے دائرہ
اثر و اقتدار سے باہر نکل جائے اور اسلامی حکومت کا محکمہ قضاء اس پر حد جاری نہ کر سکے ایسا
شخص قتل سے محفوظ ہو جائے گا.پس اس امر کے سمجھانے کے لئے یہ ضرورت نہ تھی کہ قتل کا
لفظ چھوڑ کر موت کا لفظ استعمال کیا جاتا اور قتل کے حکم کو ایسا منفی کر دیا جاتا کہ سوائے مولوی
ظفر علی خان صاحب کے دماغ کے اس کو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا.اگر اس آیت میں یہی منشاء تھا کہ قتل اور طبعی موت دونوں صورتوں کی صراحت کر
دی جائے تو اس جگہ بھی وہی طریق اختیار کیا جاتا جو ایسے موقعوں پر قرآن شریف
میں دوسرے مقامات میں اختیار کیا گیا ہے نہ یہ کہ ایک غیر ضروری استثناء کی وضاحت کے
لئے عام اور ضروری حکم کو اخفاء کے ایسے پردے میں چھپا دیا جا تا کہ کبھی بھی کسی انسان کی
عقل وہاں تک نہ پہنچ سکتی.اگر قتل اور طبعی موت دونوں صورتوں کے بیان کی ضرورت پیش
آئے تو قرآن دونوں صورتوں کے اظہار کے لئے ایسا نہیں کرتا کہ قتل اور موت کے لئے
صرف موت کا ہی لفظ استعمال کرے بلکہ دونوں لفظوں کو الگ الگ استعمال فرما کر صحیح
مفہوم کو واضح فرماتا ہے.جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ آل عمران میں فرماتا ہے:.وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ
Page 81
78
أفَأَبِنْ مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمُ (ال عمران: 145)
اور محمد صرف ایک رسول ہے اس سے پہلے سب رسول فوت ہو چکے ہیں.پس اگر وہ
وفات پا جائے یا قتل کیا جائے تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جاؤ گے.اگر محض موت کے لفظ میں دونوں مفہوم موجود تھے اور دونوں کی صراحت کے لئے
یہی ایک لفظ کافی تھا تو پھر قتل کا لفظ بلا وجہ کیوں بڑھایا گیا ؟
پھر قتل کے لفظ کی جگہ موت کا لفظ اختیار کرنے کی دوسری حکمت مولوی صاحب یہ
بیان فرماتے ہیں کہ تا یہ آیت ان مرتدین کی حالت پر بھی منطبق ہو جائے جو کسی غیر مسلم
حکومت کے ماتحت ہونے کے باعث شرعی سزائے قتل سے محفوظ رہتے ہیں.مثلاً جس
طرح آج کل ہندوستان کے حلقہ ارتداد کے مرتدین محفوظ و مصون ہیں.مولوی صاحب! اس آیت کریمہ کو پھر نظر اٹھا کر دوبارہ پڑھیں اور بتائیں کہ اس
میں اول مخاطب کون لوگ ہیں؟ کیا وہ جو اسلامی حکومت میں بودو باش رکھتے تھے یا وہ جو
ہندوستان یا چین میں سکونت رکھتے تھے ؟ جب اول مخاطب وہ لوگ تھے جن میں سے
ارتداد اختیار کرنے والوں پر بقول مولوی صاحب قتل کی سزا جاری کرنے چاہیے تھی تو پھر کیا
وجہ ہے کہ قتل کے حکم کی تو وضاحت نہ کی گئی جس کی وضاحت کی سب سے پہلے ضرورت تھی
اور ہندوستان کے حلقہ ارتداد کے مالکانوں کے متعلق وضاحت کر دی گئی کہ ان
کو قتل نہیں کیا
جائے گا.یہ تو ایسا مسئلہ تھا کہ اس کی نسبت دیو بند کا ایک ادنیٰ درجہ کا مولوی بھی نہایت
آسانی سے اجتہاد اور قیاس کر سکتا تھا.اصل ضرورت تو عام مرتدین کے متعلق فیصلہ سُنانے
کی تھی اس کی تو وضاحت نہ کی گئی اور استثنائی صورتوں پر زور دیا گیا.مولوی صاحب! آپ ادھر ادھر کیوں ہاتھ پاؤں مارتے ہیں؟ کیوں ایک آیت
قرآنی کے صاف مفہوم سے بچاؤ ڈھونڈنے کے لئے اس کو بلاضرورت استثنائی صورتوں پر
چسپاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیوں دیانت داری سے صاف طور پر اقرار نہیں کر
Page 82
79
لیتے کہ یہ آیت سب مرتدین کے متعلق ہے اور قیمت کا لفظ اور صرف اخروی سزا کا ذکر
صاف طور پر بتلا رہے ہیں کہ مرتد کی سزا قتل نہیں ہے.یہ آیت بطور ایک تحذیر کے نازل
ہوئی ہے اور اگر مرتد کے لئے قتل سزا مقرر ہوتی تو یہ اس کے ذکر کا عین محل تھا مگر اس موقع
پر اس سزا کا ذکر نہ ہونا صاف بتاتا ہے کہ اسلام میں ارتداد کی سزا قتل نہیں ہے.دیکھو
صاحب روح البیان اس آیت کریمہ کے متعلق کیا لکھتے ہیں:.هو تحذير من الارتداد وفيه ترغيب فى الرجوع الى الاسلام بعد
الارتداد الى حين الموت.( روح البیان جلد نمبر 1 صفحہ 227)
اس آیت میں ارتداد سے ڈرایا گیا ہے نیز اس بات کی ترغیب دی گئی ہے کہ وہ ارتداد
سے رجوع کر کے پھر اسلام کی طرف لوٹ آویں اور یہ موقع ان کو آخری دم تک
حاصل ہے.“
نہایت تعجب کی بات ہے کہ رحیم کریم خدا تو مرتدین کو زندگی بھر کی مہلت دے تاوہ
ارتداد سے رجوع کر کے اسلام قبول کر لیں اور اس طرح اُخروی عذاب سے کسی طرح بچ
جاویں.لیکن ہمارے علماء میں سے بعض تو یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ انہیں فورا قتل کر دیا جائے
ایک دم مہلت کی بھی ضرورت نہیں اور بعض زیادہ سے زیادہ تین دن کی مہلت دینے پر
بڑی مشکل سے راضی ہوتے ہیں.مولوی صاحب کا عقیدہ خواہ کچھ ہی ہو مگر قرآن شریف کی آیات پر جب انہوں نے
جرح کی ہے تو اپنے ضمیر اور کانشنس کوعمد بالائے طاق رکھ کر صرف اپنی قلم کے زور سے سفید
کو سیاہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے.خود ان کا قلب جانتا تھا کہ جو کچھ میں لکھ رہا ہوں
صرف میری سینہ زوری ہے اور ایسے موقع پر ضروری ہے کہ انسان سے کسی وقت بچ بھی نکل
جائے کیونکہ عمد أغلط بیانی کی جائے تو اس کو پورے طور پر نباہنا مشکل ہوتا ہے اور ایسے لوگوں
کا حافظہ بہت کمزور ہوتا ہے ان کو یاد نہیں رہتا کہ ابھی ہم کیا کہہ آئے ہیں.چنانچہ اسی آیت
Page 83
80
پر بحث کرتے ہوئے انہوں نے اپنے عدم حافظہ کا عجیب ثبوت دیا ہے اس موقع پر انہوں
نے ارتداد کے متعلق تین آیات پر جرح کی ہے اور آیت زیر بحث اس سلسلہ میں آخری
آیت ہے جس کے متعلق انہوں نے اپنے ضمیر کے خلاف اس امر پر زور دیا ہے کہ یہاں
قیمت کے معنے عام مرتدین کے لئے قتل کے ہی ہیں.لیکن جونہی وہ اس آیت پر اپنی بحث
کو ختم کر چکتے ہیں ان کے سارے دلائل فوراً ان کے حافظہ سے نکل جاتے ہیں اور جو کچھ
تکلف سے انہوں نے ثابت کرنا چاہا تھا وہ سب ان کو فراموش ہو جاتا ہے اور ان تینوں
آیات پر بحث ختم کرنے کے بعد پہلی بات جو ان کے قلم سے نکل جاتی ہے وہ یہ ہے:.بلا شبہ ان تینوں آیات قرآنی میں سزائے قتل کا کوئی ذکر نہیں
مولوی صاحب! آپ بھول گئے.تیسری آیت میں تو ضرور سزائے قتل کا ذکر ہے
کیونکہ آپ نے بڑی کوشش سے یہ ثابت کرنا چاہا تھا کہ یہاں عام مرتدین کے لئے موت
کے معنے طبعی موت نہیں بلکہ قتل کے ہیں اور آپ نے بڑی حکمتیں بیان فرمائی تھیں کہ یہاں
خدا تعالیٰ نے بجائے قتل کے موت کا لفظ کیوں اختیار کیا؟
مولوی صاحب! حافظہ نباشد والی بات سچ ہے میں نے یونہی آپ کے اس دعوئی
کی تردید کی کوشش کی.آپ نے تو خود ہی اپنے سارے لکھے لکھائے پر خط نسخ کھینچ دیا
تھا کہ بلا شبہ ان تینوں آیات قرآنی میں سزائے قتل کا کوئی ذکر نہیں.“
قرآن شریف کی جن تین آیات کی نسبت مولوی ظفر علی خان صاحب اعتراف
کرتے ہیں کہ بلا شبہ ان تینوں آیات قرآنی میں سزائے قتل کا کوئی ذکر نہیں، انہی میں
سے تیسری آیت میں سے جس پر میں ابھی بحث کر چکا ہوں، ایک دیوبندی مولوی
صاحب اخبار زمیندار مؤرخہ 5 اکتوبر 1924ء میں اپنی منطق کے زور سے اس امر کا
ثبوت پیش کرتے ہیں کہ مرتد کی سزا قتل ہے.پہلے مولوی صاحب نے تو قیمت سے قتل
مرتد کا ثبوت نکالا تھا مگر اس دوسرے مولوی صاحب نے اس سے بھی زیادہ کمال دکھایا
Page 84
81
ہے.انہوں نے اس آیت کے ایک ایسے ٹکڑے سے قتل کا حکم نکالا ہے جہاں کسی دوسرے
شخص کے وہم میں بھی یہ بات نہیں آسکتی کہ یہاں سے بھی قتل کا حکم نکالا جا سکتا ہے.أوليك حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ (التوبة 69)
سیہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا کے متعلق بھی اور آخرت کے متعلق بھی ضائع ہو گئے.ناظرین تعجب کریں گے کہ ان الفاظ سے قتل کا حکم کس طرح مستنبط ہو سکتا ہے.مگر
جن مولوی صاحب کا ذکر کر رہا ہوں وہ تو فرماتے ہیں کہ حبط اعمال کے بجر قتل کے کوئی اور
معنی ہو ہی نہیں سکتے.مولوی صاحب موصوف لکھتے ہیں کہ
فی الدنیا سے ضرور یہ مفہوم نکلا کہ مرتد کے اعمال جن کو وہ دنیا میں کرتا ہے سب
کے سب ارتداد کی وجہ سے باطل ہوں گے اور اعمال دینویہ کے بطلان کا امکان اس وقت
تک نہیں ہو سکتا جس وقت تک کہ اس کا بدن جو کہ مبدائے اعمال دنیو یہ ہے موجود رہے.الہذا حط فی الدنیا کی سزا کے معنے بجز اعدام کے کچھ نہیں ہو سکتے “
مجھے اس عجیب غریب تفسیر پر جرح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں صرف مولوی
صاحب سے اتنا پوچھتا ہوں کہ اگر آپ کے یہ معنے درست ہیں تو کیا ان سب لوگوں کو جن
کے حبط اعمال کا ذکر قرآن شریف کی آیات میں پایا جاتا ہے بموجب نص قرآن سنگسار
کرنا چاہئیے ؟ مولوی صاحب کیا فتویٰ دیتے ہیں ایسے لوگوں کے بارہ میں جن کا ذکر
قرآن شریف کی مندرجہ ذیل آیات میں ہے:.(1) وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِى
الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ (المائدة:6)
اور جو ایمان کی باتوں کو نہ مانے تو اس کا کیا کرایا اکارت ہے اور آخرت میں بھی وہ
نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا.(۲) وَلَوْ اَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ (الانعام: 89)
Page 85
82
اور اگر یہ لوگ شرک کرتے تو ان کا سارا کیا کرایا ان سے ضائع ہو جاتا.(۳) مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَوةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا
وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ أُولَيْكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمُ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ
وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَيُحِلُّ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ) (هود: 17،16)
جن کا مطلب دنیا کی زندگی اور دنیاوی رونق ہوتی ہے ہم ان کا بدلہ یہیں دنیا میں ان کو
پورا پورا دے دیتے ہیں اور وہ دنیا میں کسی طرح گھاٹے میں نہیں رہتے.لیکن یہ وہ لوگ
ہیں جن کے لئے آخرت میں دوزخ کے سوا اور کچھ نہیں اور ان کے دنیا کے عمل سب
اکارت گئے اور ان کا ر کیا کرا یا سب لغو.(۴) وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا اهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوْا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ
إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَسِرِينَ) (المائدة: 54)
اور جب (مسلمانوں پر منافقوں کا نفاق کھل جائے گا تو ) مسلمان (ان کے حال پر
افسوس کر کے آپس میں ) کہیں گے کہ کیا یہ وہی لوگ ہیں جو بڑے زور سے اللہ تعالیٰ کی
قسمیں کھاتے اور ہم سے کہا کرتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں.ان کا سارا کیا کرایا
اکارت ہوا اور وہ نقصان میں آگئے.(۵) وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوا بِابْتِنَا وَ لِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ
هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (الاعراف: 148)
اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو اور لقاء آخرت کو نہ مانا ان کا کیا کرایا سب اکارت،
یہ سزا ان کو انہی کے اعمال کی دی جائے گی.(4) مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسْجِدَ اللَّهِ شُهِدِيْنَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ
بالكفر أوليكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفي النَّارِ هُمْ خَلِدُونَ (التوبة 17)
مشرکوں کو کوئی حق نہیں کہ اللہ تعالی کی مسجدیں آباد رکھیں اور اپنے اوپر کفر کی گواہی بھی
Page 86
83
دیتے جاویں.یہی لوگ ہیں جن کا کیا کرایا سب اکارت ہوا اور یہی لوگ ہمیشہ دوزخ
میں رہنے والے ہیں.(۷) أُولَيكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
وأوليكَ هُمُ الخيرُونَ (التوبة (69)
منافقوں کی نسبت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جن کا ر کیا کرا یا سب اکارت ہو
گیا دنیا اور آخرت میں اور یہی لوگ ہیں نقصان پانے والے.(۸) أولَيْكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِايَتِ رَبِّهِمْ وَلِقَابِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ
فَلَا تُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيِّمَةِ وَزُنا (الكهف: 106)
یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں اور اس کی ملاقات کو نہ مانا تو ان کا سب
کیا کرایا اکارت ہو گیا.تو ہم ان کے لئے قیامت کے دن کوئی تول قائم نہ کریں گے.(۹) يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوْا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ
وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ
أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ) (الحجرات:3)
مسلمانو! اپنی آوازوں کو پیغمبر کی آواز سے اونچا نہ ہونے دو اور نہ اس کے ساتھ بہت
زور سے بات کرو جیسا کہ تم ایک سے ایک آپس میں زور سے بولا کرتے ہوتا ایسا نہ ہو
کہ تمہارا کیا کرایا سب اکارت ہو جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو.(١٠) أُولَكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ (الاحزاب:20)
یہ لوگ ایمان لائے ہی نہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے عمل اکارت کر دیئے.(۱۱) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ (محمد: 10)
یہ اس سبب سے ہے کہ انہوں نے اس کلام کو جو خدا تعالیٰ نے اتارا نا پسند کیا.سوخدا تعالیٰ نے ان کے عمل اکارت کر دیئے.
Page 87
84
چھٹی آیت
وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ
ط
الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ (البقرة: 144)
اور (اے پیغمبر) ! جس قبلہ پر تم (پہلے) تھے ( یعنی بیت المقدس) یا جس قبلہ پر تم ہو
(یعنی کعبہ) ہم نے اس کو اس غرض سے مقرر کیا تھا تا ہم ظاہر کر دیں کہ کون رسول کی
پیروی کرتا ہے اور کون اپنے الٹے پاؤں پھر جاتا ہے.یہ ایک تاریخی واقعہ ہے کہ جب تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے
اور مدینہ میں ہجرت کے بعد قریباً ڈیڑھ سال تک مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس رہا.یعنی
نماز میں بیت المقدس کی طرف منہ کیا جاتا تھا اس کے بعد بیت المقدس کی بجائے مکہ معظمہ
قبلہ مقرر کیا گیا.یہ دونوں قبلے بطور ابتلاء کے تھے.مکہ میں کوئی یہودی نہیں تھا اور مکہ کے
لوگ کعبہ کی عزت کرتے تھے اور نسلاً بعد نسل اس کو اپنا دینی مرکز سمجھتے تھے اور ان کے لئے
یہ بہت مشکل تھا کہ کعبہ کو چھوڑ کر وہ بیت المقدس کو جو یہود کا قبلہ تھا اپنا قبلہ مقرر کریں اور
صرف ایسے ہی لوگ کعبہ کو چھوڑ کر بیت المقدس کی طرف منہ پھیر سکتے تھے جو سچے دل سے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرنے کے لئے تیار تھے.خواہ وہ ان کے طبعی
میلان اور ان کی روایات اور مذہبی جذبات کے کیسے ہی خلاف کیوں نہ ہو.اس لئے مکہ
میں اہلِ مکہ کے لئے بیت المقدس کا قبلہ ایک امتحان تھا.اور اس امتحان میں وہی پاس ہو
سکتے تھے جو مخلص مومن ہوتے تھے.لیکن جب مدینہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
تشریف لائے تو حالات بالکل اس کے خلاف تھے.یہاں یہود کی قومیں آباد تھیں جو بیت
المقدس کو اپنا قبلہ بھتی تھیں اور ان کے لئے بیت المقدس سے منہ موڑ کر کعبہ کی طرف منہ کرنا
ایک موت تھی.مگر بیت المقدس کی طرف منہ کرنا عین ان کی مرضی اور خواہش کے مطابق
Page 88
85
تھا اور اس کی طرف مسلمانوں کے ساتھ مل کر منہ کرنا ان کے لئے چنداں دشوار نہ تھا اور
بہت سے یہودی منافقانہ طور پر مسلمانوں میں ملنے شروع ہو گئے اور اپنے آپ کو مسلمان
ظاہر کرنا شروع کیا ایسے لوگوں کے امتحان کے لیے اور منافقوں اور کمزوروں کو مخلصین کی
جماعت سے الگ کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا کہ بیت المقدس جو چودہ پندرہ
سال سے مسلمانوں کا قبلہ مقرر تھا اس کو ترک کر دینے کا حکم دیا.پس یہ دونوں قبلے بطور
ابتلاء کے مقرر کئے گئے اور اس ابتلاء کی غرض اللہ تعالیٰ یہ بیان فرماتا ہے لِنَعْلَمَ مَنْ
يَتَّبِعُ الرَّسُوْلَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ (البقرة:144) تاہم یہ ظاہر کر دیں کہ رسول کا
سچا متبع کون ہے اور کون اپنی ایڑیوں پر واپس لوٹ جاتا ہے.پس اس آیت کریمہ سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ جن لوگوں کے
دلوں میں سچا ایمان نہیں ہے اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں وہ اسلام میں
سے نکل جائیں اور مسلمانوں کی جماعت میں صرف مخلصین کا گروہ باقی رہے اور اللہ
تعالیٰ خود ایسے سامان پیدا کرتا ہے جس کی رو سے کچھ لوگ مسلمانوں میں سے نکل
جائیں اور اسلام کو چھوڑ دیں.غرض خدا تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ جو لوگ ارتداد اختیار
کرنا چاہیں وہ بڑی خوشی سے مرتد ہو کر اسلام سے الگ ہو جاویں.یہی خدا تعالیٰ کا
منشاء ہے تا اسلام خس کم جہاں پاک کا مصداق ہو مگر قتل مرتد کے حامی اسلام کی
طرف ایسی تعلیم پیش کرتے ہیں جس کا نتیجہ اس کے بالکل برعکس ہے.یعنی یہ کہ
جھوٹے اور بے ایمان لوگ اسلام کے اندر ہی شامل رہیں اور وہ کبھی اسلام کو نہ
چھوڑیں.پس ایسی تعلیم اس خدائے قدوس کی نہیں ہو سکتی ہے جو چاہتا ہے کہ ایسے
لوگ اسلام میں سے نکل جائیں اور خود ان کے نکالنے اور اسلام سے خارج کرنے
کے سامان پیدا کرتا ہے.تفاسیر سے معلوم ہوتا ہے کہ تحویل قبلہ کے موقع پر جواللہ تعالیٰ کا اس حکم سے منشاء تھا
Page 89
86
وہ پورا ہوا اور بہت سے لوگ اسلام سے مرتد ہو گئے.تفسیر ابن جریر جلد نمبر 2 صفحہ 8
میں لکھا ہے:.حتى ارتد" فيما ذكر رجال ممن كان قد اسلم
پھر اسی تفسیر کے صفحہ 9 پر لکھا ہے:."
قال ابن جريج بلغنى ان ناساممن اسلم رجعوا فقالوا مرة ههنا
ومرة ههنا.(ابن جرير جلد نمبر 2 صفحه 9)
مگر اس امر کا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ ان مرتدین کو قتل کی سزا دی گئی ؟ پس یہ آیت
بھی اس بات
کا قطعی ثبوت ہے کہ مرتدین کی سزا اسلام میں قتل نہیں ہے.ساتویں آیت
يَايُّهَا الَّذِينَ مَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ
يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَفِرِينَ
يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَا بِهِ ذَلِكَ فَضْلُ
اللَّهِ
يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ) (المائدة: 55)
مسلمانو! تم میں سے اگر کوئی اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ تعالیٰ (اس کے بدلہ میں )
ایک ایسی قوم لے آئے گا جن کو وہ دوست رکھتا ہوگا اور اس کو وہ دوست رکھتے ہوں گے،
مسلمانوں کے ساتھ نرم، کافروں کے ساتھ کڑے.اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوشش کرنے
والے ہوں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا کچھ باک نہیں رکھیں گے.یہ
خدا کا فضل ہے جس کو چاہے دے اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا اور بڑا جانے والا ہے.اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ مومنوں کو بشارت دیتا ہے کہ اگر کوئی بدقسمت تم میں
سے مرتد ہو جائے تو تمہیں فکر مند نہیں ہونا چاہیے بلکہ تمہیں خوش ہونا چاہیے کیونکہ اگر ایک تم
Page 90
87
میں سے ارتداد اختیار کر کے جماعت اسلامی سے نکلے گا تو اس کے عوض میں اللہ تعالیٰ مخلص
اور مجاہد مومنین کی ایک جماعت لائے گا.یہ آیت کریمہ مدینہ میں اتری جہاں کہ اسلامی حکومت قائم ہو چکی تھی مگر اللہ تعالیٰ
مسلمانوں
کو یہ نہیں کہتا کہ اگر تم میں سے کوئی ارتداد اختیار کرے تو تمہیں ایسے شخص کو مجبور
کرنا چاہئیے کہ وہ اسلام میں ہی رہے اور اگر وہ اسلام میں داخل ہونے سے انکار کرے تو
اسے قتل کر دینا چاہیے بلکہ فرماتا ہے کہ ایسے موقع پر تمہیں کچھ غم نہیں کرنا چاہئیے کہ کیوں یہ
شخص اسلام کو چھوڑتا ہے اگر وہ اسلام کو چھوڑ نا چاہتا ہے تو اسے چھوڑ دو.اللہ تعالیٰ ایک
ارتداد کرنے والے کے بدلے میں ایک جماعت تمہیں دے گا.جب یہ صورت تھی مسلمانوں کو کیا ضرورت تھی کہ مرتدین کو مجبور کریں کہ وہ اسلام
میں دوبارہ داخل ہوں اور مسلمانوں کی جماعت میں ایک منافق کا اضافہ کر کے خدا کے اس
فضل کو روکیں جس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے اسلامی جماعت میں ایک مخلص قوم کا اضافہ کرنا
تھا.پس اس آیت کریمہ کا مفہوم بھی یہی ظاہر کرتا ہے کہ مسلمانوں
کو یہ حکم نہیں ہے کہ وہ قتل
کی دھمکی دے کر لوگوں کو ارتداد سے روکیں اور ارتداد اختیار کرنے والوں کو قتل کر دیں.آٹھویں آیت
وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتُبِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّنْ بَعْدِ ايْمَانِكُمْ
كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ (البقرة: 110)
مسلمانو! اکثر اہل کتاب باوجود یکہ ان پر حق ظاہر ہو چکا ہے پھر بھی اپنے دلی حسد کی
وجہ سے چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان لائے پیچھے پھر تم کو کافر بنا دیں.اس آیت کریمہ میں بھی یہ موقع تھا کہ مسلمانوں کو ڈرایا جا تا کہ اگر تم یہود کے بہکانے سے
اسلام سے پھر گئے تو تمہیں قتل کی سزادی جائے گی مگر یہاں کسی ایسی سزا کا ذکر نہیں.علاوہ ازیں یہود کا
Page 91
88
حسد کی وجہ سے یہ خواہش کرنا کہ کسی طرح مسلمان اپنے دین کو چھوڑ کر اپنا پہلا کفر اختیار کر لیں یہ ظاہر
کرتا ہے کہ اس طرح دین کے چھوڑنے والوں کو کوئی سزا نہیں دی جاتی ہے.علاوہ ازیں اگر ارتداد کی سزا قتل ہوتی تو اللہ تعالیٰ یہ فرما تا کہ یہ یہود تمہارے دشمن
ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں مرتد بنا کر قتل کروا دیں.پس اس آیت کریمہ کا مفہوم بھی اسی
امر پر دال ہے کہ مرتدین کو تل نہیں کیا جاتا تھا.نویں آیت
وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا (ال عمران : 145)
اور جو اپنے الٹے پیروں کفر کی طرف لوٹ جائے گا تو وہ خدا تعالیٰ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا.یہ آیت کریمہ بھی ظاہر کرتی ہے کہ مرتد کو قتل نہیں کیا جائے گا کیونکہ اول تو یہاں
باوجود موقع ہونے کے کسی ایسی سزا کا ذکر نہیں کیا گیا.دوسرے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ ایسا
شخص خدا کا یعنی اسلام اور مسلمانوں کا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا ظاہر کرتا ہے کہ ارتداد کی سزا اقل
نہیں تھی کیونکہ اگر ایک شخص نے مرتد ہوتے ہی قتل کیا جانا تھا تو پھر بگاڑنے کا سوال ہی پیدا
نہیں ہو سکتا تھا جس نے فورا قتل ہو جانا ہو وہ کسی کا کیا بگاڑ سکتا ہے؟
دسویں آیت
وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيْمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ (البقرة: 109)
اور جو ایمان کے بدلے کفر اختیار کرے تو وہ سیدھے رستہ سے بھٹک گیا.یہاں بھی اس بات کا موقع تھا کہ اگر ارتداد کی کوئی دنیوی سزا تھی تو اس کا ذکر
کیا جاتا.یہاں صرف اتناہی بتایا گیا ہے کہ ایسا شخص سید ھے راستے سے بھٹک جاتا ہے اور
یہ ایسی چیز ہے جس کے لئے صرف اُخروی سزا ہوسکتی ہے.جوشخص سید ھے راستے سے
Page 92
89
بھٹک جائے اس کو قتل نہیں کر دیتے بلکہ وہ اپنی غلطی کا خمیازہ آخرت میں بھگتا ہے.صرف
استہ سے بھٹک جانا ایسا فعل نہیں جس کے لئے انسانی فطرت قتل کی سزا تجویز کرے.ایک معمولی فطرت کا انسان بھی اس سے کراہت کرے گا کہ کسی شخص کو محض صحیح راستہ سے
بہک جانے کی وجہ سے قتل کر دیا جائے چہ جائیکہ اسلام جیسے پاکیزہ اور مطہر مذہب کے
متعلق یہ خیال کیا جاوے کہ وہ ایسے فعل کے لئے قتل کا حکم دیتا ہے.پس یہ آیت کریمہ بھی
دوسری آیات قرآنی کی طرح اس اتہام کو بے بنیاد ثابت کرتی ہے کہ ارتداد کی سزا اسلام
میں
قتل ہے.
Page 93
90
حامیان
قتل مرتد کے دلائل پر نظر
اب ہم قرآن شریف کی تعلیم کے مختلف پہلوؤں پر نظر کر چکے ہیں اور دیکھ چکے ہیں
که قرآن شریف اول سے لے کر آخر تک ضمیر کی آزادی کے اصول
کو قائم رکھتا ہے اور کسی
قسم کے جبر واکراہ کی اجازت نہیں دیتا.اسلامی تعلیم کے محل میں ہم مختلف دروازوں سے
داخل ہو چکے ہیں اور اس کے ایک ایک کونہ کو دیکھا ہے
کہیں بھی قتل مرتد کی تعلیم کی ذرہ بھر بھی
تائید نہیں پائی جاتی.برخلاف اس کے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تعلیم قرآن شریف کی تعلیم کے
بالکل خلاف ہے اور ایسی تعلیم کوقرآن جیسی کتاب کی طرف منسوب
کرنا ایک ظلم عظیم ہے.مولوی شبیر احمد صاحب کی پیش کردہ آیت
اب مناسب ہے کہ حامیان قتل مرتد کے دلائل کو بھی دیکھا جائے کہ ان میں کہا
تک صحت اور درستی پائی جاتی ہے.سب سے پہلے میں مولوی شبیر احمد صاحب دیو بندی
کے دعوی کو لیتا ہوں.وہ اپنے ایک رسالہ ”الشہاب میں لکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں بہت
سی آیات ہیں جو مرتد کے قتل پر دلالت کرتی ہیں.لیکن ایک آیت کریمہ میں قتل مرتد کا حکم
نہایت تصریح اور ایضاح کے ساتھ پایا جاتا ہے اور وہ آیت یہ ہے
إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلى بَارِيكُم
فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ (البقرة:55)
جس کا ترجمہ مولوی صاحب اس طرح پر کرتے ہیں.”اے قوم بنی اسرائیل ! تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں
پر ظلم کیا.تو اب خدا کی
Page 94
91
طرف رجوع کرو پھر اپنے آدمیوں
کو قتل کرو.“
اور مولوی صاحب اس آیت کی تفسیر اس طرح پر کرتے ہیں کہ قوم میں سے جن
لوگوں نے بچھڑے کو نہیں پوجا تھا ان میں سے ہر ایک نے اپنے عزیز وقریب کو جس نے
گوسالہ پرستی کی تھی اپنے ہاتھ سے قتل کیا اور اس آیت کریمہ سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ
چونکہ گوسالہ پرست مرتد ہو گئے تھے اس لئے ان پر گوسالہ پرستی کے جرم میں یہ حد جاری کی
گئی کہ ان
کو قتل کر دیا گیا اور قرون خالیہ کے جن احکام و شرائع کو قرآن نے نقل کیا ان کی
پیروی و اتباع ہمارے لئے ضروری ہے جب تک کہ خاص طور پر ہمارے پیغمبر یا ہماری
کتاب اس حکم سے ہم کو علیحدہ نہ کر دیں اس لئے ضروری ہے کہ ہم بھی اس واقعہ سے سبق
حاصل کر کے مرتدین کو قتل کر دیا کریں.پھر ساتھ ہی مولوی شبیر احمد صاحب یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ ان مقتولین نے قتل
سے پہلے تو یہ بھی کی تھی اور اس کی تائید میں یہ آیت پیش کرتے ہیں.وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوْا لَبِنْ لَّمْ
يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَسِرِينَ (الاعراف: 150)
اور جب وہ شرمندہ ہو گئے اور انہوں نے سمجھ لیا کہ وہ گمراہی میں پڑ گئے تھے تو انہوں
نے کہا اگر ہمارا رب ہم پر رحم نہ کرے گا اور ہمیں معاف نہ کرے گا تو ہم نقصان اُٹھانے
والوں میں سے ہوجائیں گے.مگر ساتھ ہی فرماتے ہیں کہ اگر چہ وہ تائب بھی ہو گئے مگر باوجود تو بہ کے ان کو قتل
کر دیا گیا.فرماتے ہیں کہ ان مقتولین کی تعداد ہزاروں سے کم نہیں تھی اور ان
کو محض ارتداد
کے جرم میں نہایت اہانت اور ذلت کے ساتھ قتل کیا گیا اور تو بہ بھی ان کو خدائی سزا سے
محفوظ نہ کر سکی.مولوی صاحب کے نزدیک قاتل وہ لوگ تھے جو بنی اسرائیل میں سے اس
گوسالہ پرستی میں شریک نہیں ہوئے تھے.لیکن جو لوگ شریک ہوئے تھے ان میں سے
Page 95
92
ایک متنفس کو بھی زندہ نہ چھوڑا گیا اور باوجود تو بہ کے سب کو ایک ہی دن میں
قتل کر دیا گیا.نہیں نہیں.میں بھول گیا ایک کو چھوڑ دیا گیا یعنی سامری کو.باجود یکہ وہ اس گوسالہ پرستی کا
بانی مبانی تھا قتل نہ کیا گیا.( بلکہ اس کو بجائے قتل کے بائیکاٹ کی سزا دی گئی.غالباً اس
لئے کہ دوسرے تائب ہو گئے تھے اور یہ تائب نہیں ہوا تھا.)
مولوی صاحب کی اس تفسیر پر پہلے تو میں یہ سوال کرتا ہوں کہ مولوی صاحب کو یہ
کہاں سے معلوم ہوا کہ گوسالہ پرستوں کو قتل کرنے کا حکم ان لوگوں کو دیا گیا جو گوسالہ پرستی
میں شریک نہیں تھے؟ یہ ان کو کس طرح معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل کے کیمپ میں دو گروہ تھے
ایک وہ جو گوسالہ پرستی میں شریک ہوئے اور ایک وہ جو اس سے مجتنب رہے؟ ایسے گروہ کا
نہ تو قرآن شریف سے پتا چلتا ہے نہ بائبل سے.پس اگر مولوی صاحب اپنی تفسیر اور
استدلال
کو صحیح ثابت کرنا چاہتے ہیں تو ان کا یہ فرض ہے کہ پہلے یہ ثابت کریں کہ جس گروہ
کو قتل کی سزا سے مستثنیٰ کیا گیا تھا اور جن کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ گوسالہ پرستوں
کو قتل کر دیں وہ
اس شرک میں شریک نہیں ہوئے تھے ؟ جب تک مولوی صاحب اس گروہ کے وجود کا یقینی
اور قطعی ثبوت پیش نہیں کریں گے.ان کی تفسیر اس قابل نہیں کہ اس کی طرف توجہ کی
جاوے.اور ان کا استدلال سراسر باطل ہے.دور جانے کی ضرورت نہیں خود وہ آیت جس سے انہوں نے یہ استدلال کیا ہے
کہ ہر ایک گوسالہ پرست کو قتل کیا گیا تھا اور صرف انہی لوگوں
کو مستثنیٰ کیا گیا تھا جو گوسالہ
پرستی میں شامل نہیں ہوئے تھے ان کے معنوں کو رڈ کر رہی ہے.کیونکہ اس سے صاف
ظاہر ہے کہ یہ حکم انہی لوگوں کو دیا گیا تھا جو گوسالہ پرستی کے مرتکب ہوئے تھے اور وہی
لوگ اس حکم کے مخاطب تھے.مولوی صاحب نے استدلال کرتے وقت آیت کے
الفاظ کو نظر انداز کر دیا ہے.اللہ تعالیٰ تو ان لوگوں کو جن کو فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمُ کا حکم دیتا
ہے یہ جرم لگاتا ہے.اِنَّكُمُ ظَلَمْتُمُ اَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ مَگر مولوی
Page 96
93
صاحب فرماتے ہیں کہ فَاقْتُلُوا اَنْفُسَكُمْ کا حکم ان لوگوں کو دیا گیا تھا جنہوں نے
اتخاذ عجل کا ارتکاب نہیں کیا تھا.اب مولوی صاحب فرما ئیں کہ ہم کس کو سچا سمجھیں.اللہ تعالیٰ کو یا مولوی صاحب کو؟
غرض اگر بفرض محال یہ مان بھی لیا جائے کہ گوسالہ پرستی کے وقت بنی اسرائیل کے
دوگر وہ ہو گئے تھے.ایک وہ جو اس فعل میں شریک ہو گئے تھے اور دوسرے وہ جنہوں نے
اس سے اجتناب کیا.تب بھی مولوی صاحب کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا.کیونکہ جس آیت میں
قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس میں وہی لوگ مخاطب ہیں جو اس کاروائی میں شریک
ہوئے تھے.پس مولوی صاحب کی یہ تفسیر کہ قاتلین وہ لوگ تھے جو اس فعل میں شریک نہیں
ہوئے تھے.خود آیت قرآنی کی رو سے غلط ٹھہرتی ہے اس لئے ان کا استدلال بھی باطل
ٹھہرتا ہے.جب قاتل بھی گوسالہ پرستی میں شریک تھے تو ان کو کیوں
قتل نہ کیا گیا؟
اگر تھوڑی دیر کے لئے مولوی صاحب کی پیش کردہ تفسیر کو صحیح بھی مان لیا جاوے
تب بھی مسئلہ ارتداد کے متعلق اس سے استدلال نہیں ہوسکتا.خود مولوی شبیر احمد صاحب
قتل مرتد کے مسئلہ کو مندرجہ ذیل الفاظ میں بیان فرماتے ہیں:
مرتد کو اولاً سمجھاؤ.اس کے شبہات کا ازالہ کرو.اگر وہ خدا کی کھلی کھلی آیات
دیکھنے اور واضح دلائل سننے کے بعد بھی اپنے معاندانہ ضد اور ہٹ دھرمی پر قائم رہے اور اپنی
ہوا و ہوس یا اوہام باطلہ کی پیروی سے باز نہ آئے تو مسلمانوں کی جماعت کو اس کے
66
زہر یلے وجود سے پاک کر دو.“
پھر اس مسئلہ کی مندرجہ ذیل مثال کے ذریعہ توضیح فرماتے ہیں :.ایک شخص اتفاقاً گھوڑے سے گر پڑا.ٹانگ ٹوٹ گئی.ہڈی کے ریزے ادھر ادھر
گھس گئے.سول سرجن کا کام یہی ہے کہ ہڈی کو جوڑے.زخم صاف کرے.پٹی باندھے
Page 97
94
اور مرہم لگائے لیکن اگر کسی تدبیر سے زخم مندمل نہ ہو سکے....تو کیا اس وقت سول سرجن کا
یہ مشفقانہ فرض نہیں ہو جاتا کہ وہ ٹانگ کے مسموم حصہ کو کاٹ کر پھینک دے.“
پھر لکھتے ہیں :.یاد رکھو کہ ارتداد ایک سخت زہریلہ مادہ ہے جو جسم مسلم میں پیدا ہو جاتا ہے.خدائی سول سرجن جب اس کی تحلیل یا اخراج کی تدبیر سے تھک جاتے ہیں.تو آخرالیل
السیف کے قاعدہ سے اس عضو فاسد کو کاٹ کر پھینک دیتے ہیں.“
اسی اصول کو دوسرے حامیان
قتل مرتد نے بھی تسلیم کیا ہے.اب مولوی شبیر احمد صاحب کے مندرجہ بالا بیانات سے ظاہر ہے کہ اگر کوئی شخص
ارتداد اختیار کرے تو اولا یہ کوشش کرنی چاہئیے کہ وہ اپنی غلطی سے تائب ہو کر پھر اسلام میں
داخل ہو جاوے لیکن اگر وہ تائب نہ ہوتو پھر بامر مجبوری اس کو قتل کر دینا چاہیئے.اب ہم
دیکھتے ہیں کہ آیت پیش کردہ سے مرتد کے متعلق مذکورہ بالا فیصلہ مستنبط ہو سکتا ہے؟ جب ہم
اس آیت کو اس تفسیر کے ساتھ پڑھتے ہیں جو مولوی صاحب موصوف نے کی ہے تو ہمیں
تعجب آتا ہے کہ مولوی صاحب نے اس آیت کو اپنے عقیدہ کی تائید میں کیوں پیش کیا
کیونکہ ان کی تفسیر تو بالکل اس اصل کے مخالف پڑتی ہے جو مولوی صاحب نے پیش کیا.کیونکہ مرتد کے متعلق مولوی صاحب کا پیش کردہ اصل تو یہ ہے کہ پہلے اسے سمجھاؤ کہ وہ
تائب ہو جائے.اگر تو بہ کرے تو اسے قتل نہ کرو.اگر تو بہ کرنے سے انکار کرے تو پھر اسے
بامر مجبوری قتل کر دو.لیکن مولوی صاحب کی تفسیر کی رو سے آیت پیش کردہ کا مطلب یہ ہے کہ مرتد کو کہو
که وہ تو بہ کرے اور جب وہ تو بہ کر چکے اور اس کی تو بہ بھی سچی تو بہ ہو تو پھر اس کے بعد اس کو
قتل کر دو.اب ناظرین خود انصاف سے بتائیں کہ آیا اس آیت سے مولوی صاحب کے
Page 98
95
اپنے پیش کردہ اصول کی تائید ہوتی ہے یا تردید.مولوی صاحب نے تو ہمیں مثالیں دے
دے کر یہ سمجھایا تھا کہ مرتد کے متعلق پہلے کوشش کرو کہ وہ تائب ہو جائے اور اس کو سمجھانے
کے لئے پورا زور لگاؤ اور جب کوئی تدبیر کارگر نہ ہو اور کامل مایوسی تک نوبت پہنچ جائے تب
لا چار ہو کر قتل کرو.مگر مولوی صاحب کی تفسیر یہ کہتی ہے کہ پہلے اس بیمار عضو کے اچھا کرنے
کی کوشش کرو اور جب وہ اچھا ہو جاوے تو پھر اس کو کاٹ دو.مولوی صاحب! آپ کی
ڈاکٹر والی مثال کدھر گئی؟ کیا اس مثال کا یہی مطلب ہے کہ ڈاکٹر کو چاہیے کہ ٹوٹے ہوئے
عضو کی پہلے اصلاح کرے اور جب اس کی اصلاح ہو جاوے اور عضو درست ہو جاوےاور
ڈاکٹر اپنے علاج میں کامیاب ہو جاوے اس کے بعد اسے چاہئیے کہ وہ اس عضو کو کاٹ کر
پھینک دے.کیا ایسا ڈاکٹر عقلمند کہلائے گا یا پاگل ؟
معلوم ہوتا ہے کہ مولوی صاحب کو خود یہ بات کھٹکی ہے اور ان کو یہ بات سوجھ گئی
ہے کہ ان کی تفسیر خود ان کی اپنے اصل کے خلاف ہے اس لئے انہوں نے ناظرین کی
آنکھوں پر یہ کہہ کر پٹی باندھنے کی کوشش کی ہے کہ اب بھی بعض اقسام مرتد کے متعلق علماء
کا یہی فتویٰ ہے کہ وہ تو بہ کے بعد بھی حداً قتل کیا جائے گا.‘ مولوی صاحب نے ایک گول
مول بات کہہ کر پردہ ڈالنا چاہا ہے.مگر ایسی چالبازیوں سے حق نہیں چُھپ سکتا.مولوی صاحب کو چاہیئے تھا کہ اس بات کو کھول کر بیان فرماتے کہ وہ کون سے مرتد
ہیں جن کے متعلق علماء کا یہ عام فتویٰ ہے کہ باوجود سچی اور خالص توبہ کے بھی ان کو محض
ارتداد کے جرم میں قتل کر دیا جاوے.تاہم دیکھ سکتے کہ آیا یہ آیت ایسے مرتدین پر چسپاں
ہوتی ہے یا نہیں؟ مولوی صاحب کو یہ بات یاد رکھنی چاہئیے.کہ بحث اس امر کے متعلق ہے
کہ آیا مرتد کو محض ارتداد کی وجہ سے قتل کرنا واجب یا جائز ہے.مولوی صاحب کا یہ دعویٰ
ہے کہ مرتد کو محض ارتداد کی وجہ سے قتل کرنا واجب ہے اور اسی امر کے ثابت کرنے کے لئے
انہوں نے قلم اٹھایا ہے اور بڑی تحدّی سے یہ دعا کیا ہے کہ میں اس دعوی کو قرآن شریف
Page 99
96
سے ثابت کر سکتا ہوں.چنانچہ وہ لکھتے ہیں :.یوں تو قرآن کریم کی بہت سی آیات ہیں جو مرتد کے قتل پر دلالت کرتی ہیں لیکن
ایک واقعہ جماعت مرتدین کے بحکم خدا قتل کئے جانے کا ایسی تصریح اور ایضاح کے ساتھ
قرآن میں مذکور ہے کہ خدا سے ڈرنے والوں کے لئے اس میں تاویل کی ذرہ گنجائش
نہیں.نہ وہاں محاربہ ہے نہ قطع طریق.نہ کوئی دوسرا جرم.صرف ارتداد اور تنہا ارتداد ہی وہ
جرم ہے جس پر حق تعالیٰ نے ان کے بے دریغ قتل کا حکم دیا ہے.“
اس دعویٰ کی تائید میں وہ ایک ایسی آیت پیش کر بیٹھے ہیں جس سے ان کی تفسیر کے
مطابق یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر ایک شخص ارتداد کرے تو اس کو پہلے سمجھاؤ کہ وہ تو بہ کرے اور
جب وہ تو بہ کر چکے تو پھر اس کے بعد اس
کو قتل کر دو.اب مولوی صاحب نے دیکھا ہے کہ
یه نتیجه خود ان کے اپنے قائم کردہ اصل کے خلاف ہے اور تمام حامیان قتل مرتد کے مسلمہ
اصول کے مخالف.تو انہوں نے اپنے اس مضحکہ خیز استدلال کی بیہودگی کولوگوں کی نظر سے
پوشیدہ کرنے کے لئے یہ حیلہ تراشا کہ بعض اقسام مرتدین کے ایسے بھی ہیں جن کے متعلق
علماء کا یہی فتویٰ ہے کہ سچی اور خالص تو بہ کے باوجود بھی ان
کو قتل کر دیا جائے.اول تو مولوی صاحب کا فرض یہ تھا کہ قتل مرتد کے متعلق جو اصل انہوں نے پیش کیا
تھا کہ مرتد کو تو بہ کا موقع دیا جائے اگر تو بہ کرے تو فبہاور نہ قتل کیا جائے.اس اصولی مسئلہ کی
تائید میں قرآن شریف سے کوئی آیت پیش کرتے.مگر وہ ایسا نہیں کر سکتے.بلکہ ایک ایسی
تفسیر پیش کی جو ان کے قائم کردہ اصول کے بالکل الٹ ہے.دوم اگر مولوی صاحب اصل
کو چھوڑ کر کسی شاذ اور استثنائی صورت کی پناہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو وہ کوئی ایسی مثال پیش
کریں جو
(۱) خالص ارتداد کی صورت ہو کسی اور چیز کی آمیزش اس میں نہ پائی جائے
( کیونکہ یہی امر ہمارے زیر بحث ہے)
Page 100
97
(۲) اس مثال میں یہ بھی ضروری ہو کہ مرتد کو تو بہ کا موقع دیا جائے اور توبہ کی تلقین
کی جائے تا کہ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمُ کے الفاظ بھی اس مثال پر چسپاں ہوسکیں.(۳) اس مثال میں یہ بھی ضروری ہو کہ وہ مرتد سچے دل سے تو بہ کرے اور اس امر
کا کوئی شک اور شبہ نہ ہو کہ منافقانہ طور پر تو بہ کر رہا ہے.کیونکہ جن لوگوں کا آیت زیر بحث
میں ذکر ہے انہوں نے حسب اقرار مولوی صاحب بچی تو بہ کی اور سچے دل سے وہ اپنی غلطی
پر نادم ہوئے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی.(۴) اس مثال میں یہ بھی ضروری ہو کہ باوجود کچی تو بہ اور مخلصانہ ندامت اور پوری
پشیمانی کے پھر بھی ایسے لوگوں کا جو اسلام کے ائمہ کہلاتے ہیں اس کے متعلق عام طور پر یہ
فتویٰ ہو کہ اس کو قتل کیا جائے اور ساتھ ہی یہ بھی فتویٰ ہو کہ ایسا مقتول اخروی عذاب سے
بچایا جائے گا.کیونکہ جن مرتدین کا آیت زیر بحث میں ذکر ہے ان میں حسب بیان مولوی
صاحب یہ سب باتیں پائی جاتی ہیں.(۵) یہ بھی ضروری ہے کہ ایسی ایک آدھ مثال نہ ہو بلکہ کئی اقسام کے مرتدین ہوں
جن میں یہ سب شرطیں پائی جاتی ہوں اور پھر بھی وہ ائمہ اسلام کے نزدیک واجب القتل
ہوں اور پھر جلتی بھی.کیونکہ انہی شرائط کے ساتھ یہ آیت اس تفسیر کے ماتحت جو مولوی
صاحب نے اس آیت کی کی ہے ایسی مثالوں پر چسپاں ہو سکتی ہے.اس جگہ یہ بھی غیر مناسب نہ ہوگا کہ بعض بڑی بڑی تفاسیر کی طرف بھی رجوع
کریں اور دیکھیں کہ ان تفاسیر کی رو سے مولوی صاحب کے اس خیال کی کہاں تک تائید
ہوتی ہے اور آیا مفسرین بھی اس قتل کو ویسا ہی قتل قرار دیتے ہیں جو مرتد کے لئے تجویز کیا
گیا ہے اور آیا ان کے نزدیک بھی مسلمان اس امر میں موسوی شریعت کے پابند ہیں.تفسیر
كبير بحواله روح البیان جلد ا صفحه ۹۳: -
وقال في التفسير الكبير وليس المراد تفسير التوبة بقتل النفس
Page 101
98
بل بیان ان توبتهم لا تتم ولا تحصل الا بقتل النفس وانما كان
كذلك لان الله تعالى أوحى الى موسى ان توبة المرتد لا تتم الا
بالقتل
یعنی تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ اس آیت میں یہ مراد نہیں کہ قتل نفس کے ذریعہ تو بہ کی
تفسیر کی گئی ہے بلکہ یہاں یہ بیان ہے کہ ان کی تو بہ اسی وقت پوری ہوسکتی ہے اور حاصل ہو
سکتی ہے جبکہ نفس کو قتل کیا جائے اور یہ بات اس طرح اس لئے تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت
موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ مرتد کی تو بہ تب ہی مکمل ہوتی ہے جب کہ اسے قتل کیا جائے.اس تفسیر کی رُو سے یہ آیت حامیان قتل مرتد اپنی تائید میں پیش نہیں کر سکتے.کیونکہ
اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ قتل تو بہ کا ایک جز سمجھا جاتا تھا اور ایک قسم کا کفارہ تھا.مگر مرتد
کے لئے جو قتل ہمارے مولوی صاحبان تجویز کرتے ہیں وہ ارتداد کا کفارہ نہیں ہے اور نہ وہ
تو بہ کا قائمقام سمجھا جاتا ہے.اس لئے اس
قتل کو اس قتل سے حسب بیان تفسیر مذکور کوئی
مناسبت نہیں.پھر روح البیان جلد اصفحہ ۹۴ میں لکھا ہے :.فقتل منهم سبعون الفا فكان من قتل شهيدا ومن بقى مغفورة ذنوبه
و اوحى الى موسى انى ادخل القاتل والمقتول الجنّة هذا على
رواية ان القاتل من المجرمين على ان معنى.فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ.ليقتل بعض المجرمين بعضا فالقاتل هو الذي بقى من المجرمين
بعد نزول امر الكف عن القتل.روى ان الامر بالقتل من الاغلال التي كانت عليهم وهي المواثيق
اللازمة لزوم الغلّ ومن الاصر وهوًا لاعمال الشاقة كقطع الاعضاء
الخاطئة وغيرها فهذه الامور رفعت عن هذه الامة تكريمًا للنبي
Page 102
99.صلى الله عليه وسلم“
تب بنی اسرائیل میں سے ستر ہزار آدمی مارے گئے اور جولوگ مارے گئے وہ سب شہید
تھے اور جو باقی رہ گئے ان کے گناہ بخش دیئے گئے اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی
طرف وحی بھیجی کہ ہم قاتل و مقتول دونوں کو جنت میں داخل کریں گے.یہ معنی اس
روایت پر مبنی ہیں کہ قاتل مجرمین میں سے تھے.اس صورت میں فاقتلوا انفسكم
کے یہ معنی ہوں گے کہ مجرمین میں سے بعض دوسرے مجرموں کو قتل کر دیں.اور جب قتل
سے رکنے کا حکم آگیا تو اس وقت جو باقی رہ گئے وہ قاتل ہوئے.“
اور یہ بیان کیا گیا ہے کہ قتل کا حکم ان طوقوں میں سے ایک طوق تھا جو بنی اسرائیل کے
گلے میں پڑے ہوئے تھے یعنی وہ پختہ اقرار جو ان سے اس طرح چمٹے ہوئے تھے جس طرح
طوق گلے میں چمٹا ہوا ہوتا ہے اور یہ حکم ان بوجھوں میں سے ایک بوجھ تھا جو ان پر ڈالے گئے
تھے یعنی اعمال شاقہ مثلاً ایسے اعضاء کا کاٹ ڈالنا جن کے ساتھ گناہ کیا جائے وغیرہ وغیرہ.اور
یہ امور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز کی خاطر امت پر سے اٹھالئے گئے ہیں.“
اس تفسیر کی رو سے بھی یہ آیت قتل مرتد کے حامیوں کے لئے کچھ مفید نہیں ہے
کیونکہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جن کو قتل کیا گیا وہ شہید ہوئے اور یہ کہ مقتل ان اعمال شاقہ
اور ان بھاری بوجھوں میں سے ہے جو پہلی امتوں پر ڈالے گئے اور جو امت محمدیہ پر سے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز کی خاطر اٹھا دیئے گئے ہیں.پس یہ آیت اس تفسیر کی
رو سے بھی قتل مرتد کے سوال سے کوئی تعلق نہیں رکھتی.کیونکہ بیان مذکورہ کے مطابق یقیل
اور ہی رنگ کا قتل تھا جواب منسوخ ہو چکا ہے اور امت محمدیہ میں اب یہ حکم جاری نہیں ہے.اسی طرح روح البیان جلد اصفحہ ۹۵ میں فَاقْتُلُوا اَنْفُسَكُمْ کے ایک اور معنے بھی
لکھے ہیں اور وہ یہ ہیں :.فاقتلوا انفسكم بقمع الهوى لان الهوى هو حيات النفس وبالهوى
Page 103
100
ادعى فرعون الربوبية وعبد بنوا اسرائيل العجل.یعنی اپنے نفسوں کو اپنی نفسانی خواہشوں کے قلمع قمع کے ذریعہ قتل کرو کیونکہ نفسانی
خواہشیں نفس کی جان ہیں.اور اپنی نفسانی خواہشوں کی وجہ سے فرعون نے خدائی کا
دعویٰ کیا اور انہی خواہشوں کی وجہ سے بنی اسرائیل نے بچھڑے کی پرستش کی.انہی معنوں کی تائید مفردات راغب کی مندرجہ ذیل عبارت سے ہوتی ہے:.قيل عنى بقتل النفس اماطة الشهوات
یعنی ایک قول یہ بھی ہے کہ قتل نفس سے مراد شہوات کا مٹانا ہے.ان معنوں کی رو سے تو قتل کا سوال ہی اٹھ جاتا ہے اور مولوی صاحب کا ایضاح
اور تصریح سب بالائے طاق دھرے رہ جاتے ہیں.مولوی شبیر احمد صاحب فرماتے ہیں کہ یہاں کسی اور معنے کی گنجائش ہی نہیں مگر پہلے
لوگ اس آیت کے اور معنے لکھ چکے ہیں جن کی رو سے قتل کا سوال ہی باقی نہیں رہتا اور
مولوی صاحب کی ساری تحدی خاک میں مل جاتی ہے.پھر فتح البیان جلد اصفحہ 11 میں لکھا ہے:.فاقتلوا انفسكم اى اجعلوا القتل متعقبا للتوبة تماما لها ، يعني فاقتلوا
انفسکم کے یہ معنے ہیں کہ قتل کے ساتھ تو بہ کی تکمیل کرو.یہ وہی معنے ہیں جو اوپر لکھے
جاچکے ہیں اور مولوی صاحب کے استدلال کو باطل کرتے ہیں.وو
پھر بحر المحیط جلد نمبر اصفحہ ۲۰۸ میں لکھا ہے.وانظر الى لطف الله بهذه الملة المحمدية اذجعل توبتها في
الاقلاع عن الذنب والندم عليه والعزم على عدم المعاودة اليه
یعنی دیکھو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ پر کیسا لطف فرمایا ہے کہ ان کے لئے تو بہ صرف یہی
ہے کہ وہ گناہ سے باز آجائیں اور اس پر پشیمان ہوں اور آئندہ کے لئے پختہ ارادہ کر
Page 104
101
لیں کہ پھر اس کا ارتکاب نہیں کریں گے.پھر لکھا ہے:." فيه ثلاثة اقوال.الاوّل الأمر بقتل انفسهم.الثاني الاستسلام
بالقتل والثالث التذليل للاهواء
اس بارے میں تین قول ہیں.اول یہ کہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ اپنے نفسوں کو قتل کر
دیں.دوم یہ کہ قتل کے لئے اپنے تئیں حوالہ کر دیا.سوم خواہشات کو دبا دیا.پھر لکھا ہے:."وقيل توبوا اليه من افعالكم واقوالكم وطاعاتكم واقتلوا انفسكم
فی طاعاته وقتل النفس عما دون الله و عن الله بانفراغ من طلب
الجزاء حتى ترجع الى اصل العدم ويبقى الحق كمالم يزل
66
(بحر المحیط جلد اصفحه ۲۰۹)
یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کے یہ معنے ہیں کہ اپنے افعال، اقوال اور طاعات سے خدا
تعالیٰ کی طرف رجوع کرو اور اپنے نفسوں کو خدا تعالیٰ کی فرمانبرداری میں فنا کر دو اور
اپنے نفس کا قتل کر دینا ماسوی اللہ سے اور اللہ تعالیٰ سے اس طور پر کہ طلب جزاء سے
فارغ ہو جاوے یہاں تک کہ اصل عدم کی طرف لوٹ آئے اور حق ہی حق باقی رہ
جائے جیسا کہ وہ ہمیشہ سے ہے.یہ تمام تفاسیر مولوی شبیر احمد صاحب کے استدلال کا ابطال کر رہی ہیں اور ان
میں سے ایک بھی نہیں جو مولوی صاحب کے لئے کچھ سہارے کا موجب ہو.کیونکہ اول
تو قتل نفس کے معنے ہی نفسانی خواہشوں کا مٹانا لکھا ہے اور جب ان الفاظ کو ظاہری قتل
کے معنے میں لیا گیا ہے تو اس کو تو بہ کا قائمقام قرار دیا گیا ہے اور اس قتل کا نام شہادت
رکھا ہے.اور لکھا ہے کہ پہلی امتوں پر اس قسم کے بوجھ ڈالے گئے تھے اور امت محمدیہ پر
Page 105
102
اللہ تعالیٰ نے یہ رحم کیا ہے کہ ان پر ایسے بوجھ نہیں ڈالے اور ان کے لئے کچی تو بہ پر اکتفا
کیا گیا ہے.اب مولوی صاحب خود فرما دیں کہ یہ تفاسیر ان کے استدلال کی تائید کرتی
ہیں یا تردید؟
یہاں یہ امر بھی قابل توجہ ہے کہ سامری کو قتل کی سزا نہیں دی گئی بلکہ اسے زندہ
رہنے دیا گیا ہے صرف اس کے ساتھ میل جول بند کر دیا گیا ہے.اگر سامری کو قتل کی سزا
دی جاتی تب بے شک مولوی صاحب کا کہیں ہاتھ پڑسکتا تھا.کیونکہ اس کی نسبت یہ
ثابت نہیں کہ وہ تائب ہوا ہو بلکہ اس کے جواب سے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس
نے دیا پایا جاتا ہے کہ اس نے کسی پشیمانی کا اظہار نہیں کیا.پس اگر اس کو قتل کیا جاتا تو
مولوی صاحب کہہ سکتے تھے کہ دیکھو سامر کی تائب نہ ہوا اور اس کو ارتداد کی سزا میں قتل کیا
گیا.لیکن یہاں تو معاملہ بالکل برعکس ہے.جو تائب ہوتے ہیں ان کو حسب تفسیر مولوی
صاحب قتل کیا جاتا ہے اور جو تائب نہیں ہوتا اور جو سب سے زیادہ مجرم ہے اس کو چھوڑ دیا
جاتا ہے اس سے مولوی صاحب مرتدین کے متعلق اگر کوئی استدلال کر سکتے ہیں تو یہ کر
سکتے ہیں کہ مرتد اگر تو بہ کرے تو اسے قتل کر دو اور اگر تو بہ نہ کرے تو اسے چھوڑ دو.یہ
استدلال اگر مولوی صاحب کے مفید مطلب ہے تو بے شک ان کو اجازت ہے کہ وہ ایسا
استدلال کرلیں مگر وہ کسی صورت میں اس آیت سے یہ نتیجہ نہیں نکال سکتے کہ مرتد اگر تو بہ
کرے تو اسے چھوڑ دو اگر تو بہ نہ کرے تو اس کو قتل کر دو.مولوی صاحب نے اپنی طرف سے اس بارے میں پیش بندی کرنے کی پوری
کوشش کی ہے.وہ سامری کے قتل نہ کئے جانے کی ایک وجہ تجویز فرماتے ہیں.مگر افسوس
که قرآن شریف ان کو کہیں ٹھہرنے نہیں دیتا.جو سہارا وہ پکڑتے ہیں قرآن شریف اسے
گرا دیتا ہے.مولوی صاحب اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے کہ کیوں سامری کو جواس
ساری شرارت کا بانی تھا قتل نہیں کیا گیا فرماتے ہیں.
Page 106
103
سامری شرارت کا ایسا ہی بانی تھا جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں
عبد اللہ بن ابی رئیس المنافقین ، قصۂ افک کا بانی اور الذی تولی کبرہ کا مصداق اعظم تھا
مگر حسب روایت صحیحہ اس پر حد قذف جاری نہ کی گئی.حالانکہ حضرت حسان بن ثابت
وغیرہ مومنین پر حد قذف جاری ہوئی.حقیقت یہ ہے کہ منافقین سب سے بڑھ کر شرارتیں
کرتے ہیں لیکن اپنے نفاق کی وجہ سے دنیا میں قانونی گرفت سے اپنے کو بچاتے رہتے
ہیں.جھوٹ بولنے اور بات بنا دینے میں ان کو کوئی باک نہیں ہوتا.ساری کارروائی کر کے
بھی قانونی زد سے اپنے کو بچالیتے ہیں.“
مولوی صاحب نے بات تو اچھی بنائی ہے مگر افسوس ! یہ عذر یہاں چل نہیں سکتا اور
مولوی صاحب حق کی زد سے اپنے کو بچانہیں سکے.اگر عبد اللہ بن ابی اپنے تئیں قانونی زد
سے بچانے میں کامیاب ہوا تو سامری اپنے تئیں نہیں بچا سکا کیونکہ اس کے خلاف تمام قوم
نے شہادت دی کہ گوسالہ پرستی کا بانی مبانی سامری ہی ہے.چنانچہ آتا ہے:.قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَّا حَمَلْنَا اَوْزَارًا
مِنْ زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَ فَنَهَا فَكَذَلِكَ الْقَى السَّامِرِئُ فَأَخْرَجَ
لَهُمْ عِجَلًا جَسَدًا لَّهُ خَوَارٌ (طه : 89،88)
ان آیات کریمہ کا ترجمہ مولوی نذیر احمد خان صاحب دہلوی نے حسب ذیل کیا ہے.”انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے ساتھ عہد شکنی نہیں کی بلکہ ہم کو یہ
معاملہ پیش آیا کہ قوم کے زیوروں کا بوجھ جو ہم پر لادا گیا تھا اب (سامری کے کہنے
سے ) ہم نے اس کو ( آگ میں لا) ڈالا اور اسی طرح سامری نے بھی (اپنے پاس کا
زیور لا ) ڈالا.پھر سامری ہی نے لوگوں کے لئے اس کا ایک بچھڑا بنا کر نکال کھڑا کیا
66
جس کی آواز بھی بچھڑے کی سی تھی.“
اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے جواب طلب کیا تو اس نے اپنے
Page 107
104
قصور کا صاف اقرار کیا اور قانون کی زد سے بچنے کے لئے وہ کوئی بات نہ بنا سکا.پھر مولوی صاحب کے عذر کا بطلان اس سے بھی ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام
نے اس کے جرم کے ثابت ہونے پر اس کو سزا بھی دی اور اس کا جواب سننے کے بعد اس
کے خلاف فیصلہ بھی کیا اور وہ فیصلہ یہ ہے:.قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَوةِ أَنْ تَقُوْلُ لَا مِسَاسَ
وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّنْ تُخْلَفَهُ (طه : 98)
چل اس زندگی میں تو تیری یہ سزا ہے کہ کہتا پڑا پھر کہ دیکھو مجھے کوئی چھونہ جانا.اور اس
کے علاوہ تیرے لئے ایک وعدہ اور ہے جو کسی طرح تجھ پر سے ملے گا نہیں.“
پس مولوی صاحب کا یہ عذر غلط ہے کہ اس نے عبد اللہ بن اُبی کی طرح قانون کی
زد سے اپنے تئیں بچالیا.اس پر عدالت نے فرد جرم لگایا اور اس کو سزا بھی دی.مگر وہ سزا
قتل کی نہیں تھی بلکہ لا مساس کہنے کی سزا تھی.مولوی صاحب کی پیش کردہ مثال سے ایک مفید نتیجہ
مولوی صاحب کی اس پیش کردہ آیت سے ایک نہایت ہی مفید نتیجہ نکلتا ہے اور وہ
یہ ہے کہ مرتد کو قتل نہ کیا جائے.کیونکہ بنی اسرائیل کے جس واقعہ کو مولوی صاحب نے بطور
مثال کے پیش کیا ہے اس میں ایک مرتد یعنی سامری کا ذکر ہے جو اپنے ارتداد پر قائم رہا.مگر پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو قتل نہیں کیا.پس اس واقعہ سے ثابت ہوتا ہے
کہ مرتد کی سزا قتل نہیں ہے کیونکہ اگر مرتد کی سزا قتل ہوتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو
ضرور قتل کرتے.پس خود مولوی صاحب کی اپنی دلیل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مرتد کی سزا
قتل نہیں.مولوی صاحب کا تہہ دل سے ممنون ہوں کہ انہوں نے یہ دلیل مجھے سمجھائی ورنہ
میرا ذہن اس طرف نہ جاتا.اب مولوی صاحب فرمائیں کہ اس دلیل کا ان کے پاس کیا
Page 108
جواب ہے؟
105
→
ان تمام بزرگوں نے جنہوں نے اس وقت قتل مرتد کی حمایت میں قلم اٹھایا ہے
آزادی ضمیر کے سوال پر بہت لے دے کی ہے اس لئے ضروری ہے کہ ان کی جرح پر بھی
ایک نظر کی جائے.آزادی ضمیر کے اصول پر سب سے زیادہ جرح کرنے والا اخبار
الجمعیۃ ہے جو جمعیۃ العلماء کا آفیشل آرگن ہے.میں اس کی جرح کو ذیل میں نقل
کرتا ہوں.اس جرح سے معلوم ہوتا ہے کہ یا تو یہ لوگ جانتے ہی نہیں کہ عرف عام میں
آزادی ضمیر کس چیز کا نام ہے اور قرآن شریف کی رُو سے اس کا مفہوم کیا ہے یا عمد اجہالت
کی راہ اختیار کرتے ہیں.الجمعية نے آزادی ضمیر کے متعلق کئی شقیں قائم کی ہیں اور
ہر ایک شق پر الگ الگ جرح کی ہے اور اس کی ساری جرح کا لب لباب یہی نکلتا ہے کہ وہ
یا تو آزادی ضمیر کا مفہوم ہی نہیں جانتایا جان بوجھ کر دھوکہ دیتا ہے.مگر تعجب کی بات یہ ہے
کہ وہ ہمیں الزام دیتا ہے کہ ہم جانتے ہی نہیں آزادی ضمیر کی کیا حقیقت ہے.اب میں
اس کی ایک ایک شق کو ناظرین کے سامنے پیش کرتا ہوں.شق اول
اگر ضمیر کی آزادی کا یہ مطلب لیا جاوے کہ ہر فر د جو رائے قائم کرے اور واقعات
پر جوحکم لگائے اور مقدمات سے جو نتائج وہ نکالے وہ اس کے حق میں صحیح اور درست ہیں اور
ہر شخص اپنی رائے پر عمل کرنے کا مکلف ہے.کسی دوسرے کی رائے کوسنا، مانا عمل کرنا
ضروری نہیں تو اس کا بطلان بدیہی اور واضح ہے.اس کا جواب یہ ہے کہ ضمیر کی آزادی کا یہ مطلب نہیں کہ جو اس شق میں بیان کیا
گیا ہے.جو لوگ آزادی ضمیر کے حامی ہیں ان میں سے کسی کا بھی یہ خیال نہیں کہ ہر
یک شخص کی رائے ضرور درست اور صحیح ہوتی ہے اور نہ کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ کسی
Page 109
106
دوسرے کی رائے کو نہ سننا چاہئیے اور نہ اس پر غور کرنا چاہئیے بلکہ آزادی ضمیر کا صرف
یہی مطلب ہے کہ اگر ایک شخص کسی امر کے متعلق کوئی خاص عقیدہ رکھتا ہے تو ہمیں
اسے مجبور نہیں کرنا چاہئیے کہ وہ اس عقیدہ کوترک کر دے.کیونکہ ایسا کرنا ایک احمقانہ
حرکت ہے.ہم جبر سے کسی کے عقیدہ کو تبدیل نہیں کر سکتے.ہاں اگر ہماری رائے میں
اس کا عقیدہ غلط ہے تو ہمیں عقلی اور نقلی دلائل کے ذریعہ سے اس کی فطرت انسانی کے
آگے اپیل کر کے کوشش کرنی چاہئیے کہ وہ اپنی غلطی کو سمجھ جائے لیکن اگر وہ ہمارے
سمجھانے کے بعد بھی اپنے غلط عقیدہ کو ترک نہیں کرتا تو ہمیں اس کے غلط عقیدہ کی وجہ
سے اس کو دکھ اور عذاب نہیں دینا چاہئیے.یہ ہے مفہوم آزادی ضمیر کا.اگر اس پر کوئی
اعتراض پڑتا ہے تو الجمعية کو اختیار ہے کہ اپنے اعتراض کو پیش کرے لیکن اس پر
اعتراض کرنا خود قرآن شریف پر اعتراض کرنا ہے کیونکہ قرآن شریف اسی امر کی تعلیم
دیتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:.(ا) فَذَكِّرُ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكَّرَةٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُضَبْطِرٍ (الغاشية: 23)
پس (اے پیغمبر ) نصیحت کر کہ تو تو صرف نصیحت کرنے والا ہے.تو ان لوگوں پر داروغہ
کے طور پر مقرر نہیں ہے.(۲) فَأَعْرِضْ عَنْ مِّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ
إِلَّا الْحَيَوةَ الدُّنْيَات (النجم: 30)
(اے رسول ) تو بھی اس شخص سے منہ پھیر لے اور اس کی پیروی نہ کر جو ہمارے ذکر
سے منہ پھیر لیتا ہے اور سوائے دنیا کی زندگی کے اور کچھ نہیں چاہتا.(۳) وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ ، أَنْتُمْ
بَرِيتُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَآنَا بَرِئَ مِمَّا تَعْمَلُوْنَ (يونس:42)
اور اگر وہ تجھے جھٹلا ئیں تو انہیں کہہ کہ میر اعمل خود میرے لئے اور تمہاراعمل تمہارے لئے
Page 110
107
فائدہ مند یا نقصان دہ ہوگا.جو کچھ میں کرتا ہوں اس سے تم بری الذمہ ہو اور جو کچھ تم
کرتے ہو اس سے میں بری الذمہ ہوں.(٢) إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ : فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا (المزمل: 20)
یہ قرآن ایک نصیحت ہے پس جو چاہے اپنے رب کی طرف جانے والا راستہ اختیار
کرلے.(۵) قُلِ اللهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَّهُ دِينِي فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ
منْ دُونِهِ (الزمر: 16:15)
(اے پیغمبر ) تو کہہ دے کہ میں اللہ کی عبادت اپنی اطاعت کو صرف اس کے لئے
وابستہ کرتے ہوئے کرتا ہوں.سو تم اللہ کے سوا جس کی چاہو عبادت کرو.شق دوم
اگر یہ معنی تسلیم کر لئے جاویں کہ ہر شخص مذہبی امور میں کامل آزاد خود مختار ہے جو
مذہب چاہے اختیار کرے اور جو عقیدہ چاہے رکھے تو ماننا پڑتا ہے کہ دنیا میں جس قدر مذہبی
اعتقادات اور مذہبی خیالات ہیں وہ سب حق و درست ہیں.اقول:
آپ
کا یہ نتیجہ صحیح نہیں.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:.قُلِ اللهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَّهُ دِينِي فَاعْبُدُوا مَا شِثْتُمْ
مِنْ دُونِهِ (الزمر:16:15)
یعنی اے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم ) لوگوں سے کہہ دو کہ میں خالص اللہ ہی کی عبادت کرتا
ہوں تم اس کے سوا جس کی چاہو عبادت کرو.
Page 111
108
کیا اس سے یہ لازم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کی عبادت کرنا حق اور
درست ہے؟
الجمعیة کو یہ معلوم ہونا چاہیئے کہ ہم تو صرف اتنا ہی کہتے ہیں جتنا قرآن شریف
فرماتا ہے یعنی ہمارا صرف اتنا فرض ہے کہ ہم لوگوں کو حق پہنچا دیں اس کے بعد ان کا اختیار
ہے چاہیں قبول کریں چاہیں قبول نہ کریں ہمیں کسی پر جبر نہیں کرنا چاہئیے.اس سے اگر
الجمعية یہ نتیجہ نکالے کہ اس طرح تمام مذاہب
کو سچا مانا پڑتا ہے تو یہ اس کی خوش فہمی ہے.شق سوم
اگر تیسرے معنی لئے جاویں کہ مذہبی عقائد کے متعلق (خواہ غلط ہوں ) دنیا میں
اس سے تعرض نہ کیا جائے گا اور اس کو سزا نہ دی جائے گی.تو اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ
جب کسی کے غلط عقیدہ پر غلطی کا حکم لگایا گیا اور فتویٰ دیا گیا کہ یہ عقیدہ اور عمل کفر ہے اور اس
کی سزا جہنم ہے تو پھر ضمیر کی آزادی کہاں رہی.اگر آزادی دیتے ہیں تو اس کے عقیدہ اور
عمل کو جائز قرار دیں.دوسرا جواب یہ ہے کہ ایسی صورت میں مذہبی سیاست کا وجود نہیں ہونا چاہیے نہ کسی
کو زنا کی سزادی جاوے.نہ چوری کی.نہ شراب خوری پر مواخذہ ہو.نہ بہتان و تہمت
پر عمل عقیدہ کی فرع ہے.اگر عقیدہ میں سزا د ہی ناجائز ہے تو فرع میں سزا دینے کے کیا
معنے ہوں گے؟
اقول:
یہ تیسرے معنے بالکل درست ہیں.یہی ہمارا مطلب ہے.مگر ان معنوں پر
الجمعية کی جرح بے بنیاد ہے.
Page 112
109
الجمعية کی یہ منطق ہماری سمجھ سے بالا تر ہے.اگر کسی کو اس کے مذہبی عقائد کی
وجہ سے دنیا میں سزا نہ دی جاوے تو اس سے کس طرح لازم آتا ہے کہ وہ عقیدہ جائز ہو گیا.سورۃ معارج میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :.فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوْا حَتَّى يُلْقُوْا يَوْمَهُمُ
الَّذِي يُوعَدُونَ (المعارج : 43)
اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کفار کو جو دین کے متعلق خوض ولعب
میں مصروف ہیں ان کے حال پر چھوڑ دو یہاں تک کہ وعدہ کا دن آ جائے.اب کیا اس سے
یہ لازم آتا ہے کہ ان کفار کا خوض ولعب جائز تھا؟
الجمعية لکھتا ہے کہ جب کسی کے غلط عقیدہ پر غلطی کا حکم لگایا گیا تو پھر ”آزادی
غلط
ضمیر کہاں رہی معلوم نہیں الجمعية نے آزادی ضمیر کے کیا معنی سمجھ رکھے ہیں.آزادی ضمیر کے اس سے زیادہ اور کوئی معنی نہیں کہ عقیدہ کے معاملہ میں کسی پر جبر نہ کیا
جاوے.یا الجمعیۃ کے اپنے الفاظ میں آزادی ضمیر کے یہ معنی ہیں کہ ”مذہبی عقائد
کے متعلق ( خواہ غلط ہوں ) دنیا میں اس سے تعرض نہ کیا جاوے گا اور اس کو سزا نہ دی
جائے گی.اب خدا را الجمعية ہمیں بتائے کہ جب آزادی ضمیر کے وہ معنی لئے
جائیں جو اس نے خود شق نمبر ۳ میں بیان کئے ہیں تو ان لفظوں کو ان معنوں میں لیتے ہوئے
کس طرح یہ لازم آتا ہے کہ جن لوگوں کو آزادی ضمیر کے اصول کی وجہ سے سزا نہ دی جائے
ان
کا عقیدہ بھی درست ہے.اگر ایک شخص کو اس دنیا میں سزا نہ دی جاوے تو اس سے یہ
کس طرح لازم آتا ہے کہ اس
کا عقیدہ درست ہے؟
پھر الجمعية لکھتا ہے کہ اگر عقیدہ کی وجہ سے سزا نہ دی جاوے تو پھر کوئی وجہ
نہیں کہ عمل کی وجہ سے کسی کو سزادی جاوے اس لئے اگر آزادی ضمیر کا اصول درست ہے تو
ایسی صورت میں مذہبی سیاست کا وجود نہیں ہونا چاہئیے.نہ کسی کو زنا کی سزادی جاوے اور نہ
Page 113
110
چوری کی.عقیدہ اور عمل دونوں میں آزدی ہونی چاہئیے.اقول:
اگر عقیدہ اور عمل دونو کا ایک ہی حال ہوتا تو اس صورت میں بے شک ضروری تھا
کہ دونو میں اس کو آزادی حاصل ہوتی.لیکن دونو کا ایک حال نہیں.جب عقائد سے گزرکر
انسان اعمال کی طرف جاتا ہے تو اس کے بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں جن کا ضرر یا فائدہ
دوسرے انسان کو پہنچتا ہے اس لئے وہ ان افعال میں اب آزاد نہیں ہو سکتا.اس کی آزادی
اس دائرہ تک محدود ہے جہاں تک صرف اس کی ذات کا تعلق ہے.لیکن جب اس کے
افعال اس دائرہ میں داخل ہو جاتے ہیں جہاں اس کی غلطی سے دوسرے لوگوں کو ضرر پہنچ
سکتا ہے تب اس کی آزادی رو کی جاتی ہے کیونکہ اب صرف اسی کی ذات کا سوال نہیں بلکہ
دوسرے لوگوں کے حقوق کا بھی سوال ہے اور اس کو کوئی حق نہیں کہ وہ دوسرے لوگوں کو
نقصان پہنچائے اور ان کے حقوق کو تلف کرے.اس لئے اگر وہ کوئی ایسا فعل کرنا چاہے گا
جس سے دوسروں
کو ضرر پہنچتا ہو تو وہاں اس کے ہاتھ کو روک دیا جائے گا اور اس کی آزادی
اس سے چھینی جائے گی.یہی اصل ہے جس پر تمام شرعی احکام کی بنیاد ہے اور تمام دنیا کی
حکومتوں کے قوانین اسی اصول پر جاری ہیں.جہاں محض اس کی ذات کا تعلق ہے وہ آزاد
ہے لیکن جہاں اس کے افعال کا اثر تمدن پر پڑتا ہے وہاں شریعت کا قانون اور ایسا ہی
انسانی حکومتوں کا قانون دخل دے گا.معترض کہتا ہے کہ اگر اسے ضمیر کی آزادی حاصل
ہے تو پھر اسے اجازت ہونی چاہئیے کہ جو چاہے کہے اور جو چاہے کرے.نہ چوری کی وجہ
سے اس کے ہاتھ کاٹنے چاہیں اور نہ زنا کی وجہ سے اسے کوڑے لگانے چاہیں اور نہ
شراب خوری کی حد اس پر جاری کرنی چاہئیے.میں کہتا ہوں کہ ان افعال میں وہ آزاد نہیں
ہوسکتا کیونکہ ان افعال کا تعلق تمدن سے ہے وہ ایسے افعال میں آزاد نہیں.ہاں عقائد
Page 114
111
میں اور ایسے اعمال میں جن کا اثر صرف اس کی ذات تک محدود ہے اس کو پوری آزادی
حاصل ہے.اگر ایک شخص خدا تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتا اور خدا کے آگے گریہ وزاری نہیں
کرتا تو ہم اس پر کوئی سزا جاری نہیں کر سکتے لیکن اگر وہ دوسرے کا مال چھینتا ہے یا زنا کا
ارتکاب کرتا ہے تو وہاں شریعت اور انسانی حکومت ضرور دخل دیں گی کیونکہ یہاں وہ تمدن کو
نقصان پہنچاتا ہے.ایسی صورت میں وہ بغیر سزا کے نہیں چھوڑا جائے گا.قرآن شریف کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ کوئی حکم نہیں دیتا جس کے ساتھ اس کی
دلیل بیان نہ کرے.چنانچہ اسی اصول کے مطابق جب ہدایت اور گمراہی کے متعلق یہ حکم
دیا ہے کہ کسی پر جبر نہ کیا جاوے وہاں یہی دلیل بیان فرمائی ہے کہ چونکہ کسی کی ہدایت یا
گمراہی سے دوسروں کے حقوق پر کوئی اثر نہیں پڑتا بلکہ اس میں صرف اسی شخص کی اپنی
ذات کا تعلق ہے اس لئے اس میں جبر سے کام نہیں لینا چاہئیے.چنانچہ اللہ تعالیٰ سورۃ الزمر
میں فرماتا ہے.إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَبَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ ۚ فَمَنِ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ
وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ (الزمر:42)
ہم نے تجھ پر لوگوں کے فائدہ کے لئے حق کے ساتھ یہ کتاب اتاری ہے پس جس
نے راہ پائی اس نے اپنا بھلا کیا اور جو گمراہ ہو گیا تو اس کی گمراہی کا نقصان اسی کو پہنچے گا
اور تو ان کا ذمہ وار نہیں ہے.“
اس آیت کریمہ میں بہت سی دیگر آیات کی طرح یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ایمان اور کفر
کے معاملہ میں جبر سے کام نہیں لینا چاہئیے اور ساتھ ہی اس کی وجہ بھی بیان کر دی ہے.یعنی
یہ کہ اگر ایک شخص راہِ راست کو اختیار کرتا ہے تو اس میں اس کا اپنا فائدہ ہے اور اگر راہِ
راست کو چھوڑتا ہے تو اس میں اس کا اپنا نقصان ہے.دوسرے لوگوں کے حقوق کا کوئی
نقصان نہیں اس لئے کوئی جبر نہیں ہونا چاہیئے.
Page 115
112
اس آیت میں الجمعیة کے اس اعتراض کا بھی جواب آ گیا ہے کہ اگر عقیدہ میں
آزادی دی جائے تو ماننا پڑتا ہے کہ ہر ایک کا عقیدہ درست ہے.یہ استدلال قرآن
شریف کی متذکرہ بالا آیت سے رڈ ہوتا ہے کیونکہ اس میں صاف بتلایا گیا ہے کہ اس
آزادی سے یہ نہیں سمجھا جاتا کہ سب کے عقائد درست ہیں اور کسی کو آخرت میں سزا نہیں
دی جائے گی بلکہ وہی راہ راست پر سمجھے جائیں گے جو خدا تعالیٰ کی بتائی ہوئی راہ کو قبول
کریں گے اور جو اس راہ کو اختیار نہیں کریں گے وہ گمراہ سمجھے جائیں گے اور اس کا بدلہ ان کو
آخرت میں مل جائے گا.اور آزادی کے صرف یہی معنے ہیں کہ ان پر جبر نہ کیا جاوے اور
اس دنیا میں عقائد کی وجہ سے ان کو سزا نہ دی جائے.کیا اسلام میں داخل ہونے کے بعد اکراہ فی الدین جائز ہے؟
الجمعية کی تمام شقوں کا تصفیہ کرنے کے بعد اب میں ان مولوی صاحبان کی
ایک اور دلیل کو لیتا ہوں جس کے ذریعہ انہوں نے قتل مرتد کو لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ
(البقرة: ۲۵۷) کے حکم سے خارج کرنے کی کوشش کی ہے.مولوی شاکر حسین صاحب سہسوانی
اپنے مضمون مندرجہ زمیندار میں تحریر فرماتے ہیں :.وو
داخل فی الاسلام کے لئے اور احکام ہیں اور خارج عن الاسلام کے لئے اور.اس بناء پر آیت شریفہ لَا اِکراہ فی الدین کا مفہوم کسی طرح بھی مفید مطلب نہیں ہے.یہ
امر کہ کسی کو زبر دستی مسلمان نہ کیا جائے کسی طرح بھی اس کو مستلزم نہیں کہ قبول اسلام کے
بعد انسان جب چاہے اس کا جو اگر دن سے اُتار کر پھینک دے.معمولی اور موٹی سی بات
ہے کہ بادشاہ وقت کسی کو زبردستی اپنی ملازمت میں منسلک نہیں کرتا.لیکن جو شخص اس کی
ملا زمت میں داخل ہو چکا ہے اس کو کبھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اپنی خوشی سے جو چاہے
کرے یا جب چاہے اس ذیل سے نکل جائے.اور جولوگ ایسا کرتے ہیں وہ حسب اعمال
Page 116
113
سزایاب ہوتے ہیں.“
میں اس بات
کو تسلیم کرتا ہوں کہ جب ایک شخص ایک دین کو قبول کرتا ہے تو اس پر
اس دین کے متعلق بعض پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں جو پہلے ان پر لازم نہ تھیں اور جب تک
وہ اس دین میں ہے وہ ان کی ذمہ داریوں سے آزاد نہیں ہوسکتا.وہ اس دین کے دوسرے
پیروؤں کی طرح ان تمام ضوابط اور قوانین کا پابند ہو گا جو اس دین نے اپنے پیروؤں کے
لئے مقرر کر رکھے ہیں اور ان کی خلاف ورزی میں وہ اسی تعزیر کا مستوجب ہو گا جو اس دین
میں ایسی خلاف ورزی کے لئے مقرر کی گئی ہے.لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ایک دفعہ
ایک دین کو قبول کرنے کے بعد پھر اس کو کبھی ترک کرنے کا اختیار نہیں رکھتا.اگر یہ قاعدہ
درست ہے کہ ایک شخص ایک دفعہ ایک مذہب اختیار کرنے کے بعد پھر اس مذہب کو کسی
صورت میں ترک نہیں کر سکتا تو یہ قاعدہ جیسا اسلام کے واسطے درست ماننا پڑے گا ویسا ہی
دوسرے مذاہب کے لئے بھی درست ماننا پڑے گا.جیسا اسلام کسی کو مجبور نہیں کرتا کہ وہ
اس میں داخل ہو لیکن جب ایک انسان اپنی خوشی سے اسے قبول کرتا ہے تو وہ اپنی مرضی سے
اس کے قوانین کا جوا اپنی گردن پر رکھتا ہے اور اپنے تئیں اس
کا پابند بنادیتا ہے کہ ان کی تعمیل
کرے اور خلاف ورزی کی صورت میں اس سزا کو برداشت کرے جو اس کے لئے مقرر کی
گئی ہے ایسا ہی دوسرے مذاہب بھی کسی کو مجبور نہیں کرتے کہ وہ ان کو اختیار کر یں لیکن اگر
ایک شخص اپنی خوشی سے ان کو قبول کرتا ہے تو وہ اپنی مرضی سے ان کے ضوابط کا جوا اپنی
گردن پر اٹھاتا ہے اور وہ پابند ہے کہ جب تک وہ اس مذہب کی پیروی کا دعویٰ کرتا ہے
اس کے قوانین کی پیروی کرے اور عدم تعمیل کی صورت میں اس تعزیر کو قبول کرے جو ایسے
موقع کے لئے تجویز کی گئی ہے.پس اس قاعدہ میں عقلاً اسلام اور دیگر مذاہب میں کوئی فرق نہیں.یہ قاعدہ اگر
معقول ہے تو سب مذاہب کے لئے عام ہونا چاہئیے اور مولوی شاکر حسین صاحب سہسوانی
Page 117
114
نے اپنے دعوی کی معقولیت ثابت کرنے کے لئے جو مثال دی ہے اس سے بھی یہی ظاہر
ہوتا ہے کہ یہ قاعدہ اسلام کے لئے خاص نہیں بلکہ سب مذاہب کے لئے عام ہے کیونکہ
اگر وہ مثال درست ہے تو وہ صرف اسلام پر چسپاں نہیں ہوتی بلکہ تمام ادیان پر.اس
لئے مولوی شاکر حسین صاحب کا پیش کردہ قاعدہ درست اور صحیح ہے تو اس سے یہ نتیجہ نکلتا
ہے کہ جس مذہب میں کوئی شخص ایک دفعہ داخل ہو جاوے خواہ اسلام یا کوئی اور مذہب پھر
اس کا کوئی حق نہیں کہ وہ اس مذہب کو کسی صورت سے ترک کر سکے.اب اگر اس کے لئے
اس مذہب سے نکلنے کا کوئی دروازہ ہے تو وہ موت کا ہی دروازہ ہے اور کوئی راہ نہیں.لیکن
یہ بداہتا باطل ہے.کیا مولوی شاکر حسین صاحب اس بات کے تسلیم کرنے کے لئے تیار
ہیں کہ اگر ایک شخص مسیحی مذہب اختیار کرے تو پھر وہ پابند ہو جاتا ہے کہ تا دم مرگ مسیحی
مذہب پر ہی قائم رہے اور اس کو کوئی حق نہیں کہ وہ مسیحی مذہب چھوڑ کر کوئی دین قبول کرے؟
مولوی صاحب ! یہ ہے نتیجہ آپ کی دلیل کا.اس سے تو لازم آتا ہے کہ جس مذہب
کو ایک دفعہ انسان قبول کرے اس کو اختیار نہیں رہتا کہ پھر اس مذہب کو ترک کر سکے.جب تک کہ وہ کسی مذہب کو قبول نہیں کرتا اس وقت تک وہ آزاد ہے جس مذہب کو چاہے
قبول کرے.لیکن جو نہی کہ وہ ایک مذہب کو قبول کرتا ہے اس کی آزادی چھینی جاتی ہے اور
وہ آزادی کا قانون جس سے وہ پہلے فائدہ اٹھا سکتا تھا اب اس سے ہمیشہ کے لئے محروم کر
دیا جاتا ہے کیونکہ اب وہ قاعدہ اس پر جاری نہیں ہوسکتا.مولوی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ
معمولی اور موٹی سی بات ہے کہ بادشاہ وقت کسی کو زبردستی اپنی ملازمت میں منسلک نہیں کرتا
لیکن جو شخص اس کی ملازمت میں داخل ہو چکا ہے اس کو کبھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ جب
چاہے اس ذیل سے نکل جائے.مولوی صاحب! بے شک یہ معمولی اور موٹی سی بات
ہے مگر کیا وجہ ہے کہ یہ معمولی اور موٹی سی بات صرف اسلام پر چسپاں ہو سکے اور دوسرے
ادیان پر چسپاں نہ ہو سکے؟ کیوں یہ مثال ہندو مذہب یا مسیحیت یا بدھ مذہب وغیر ہا پر
Page 118
115
چسپاں نہ کی جائے؟
مولوی صاحب! کیا یہ انصاف کی بات ہے کہ اس مثال کو اپنے لئے خاص کر لیں
دوسروں کو اجازت نہ دیں کہ وہ بھی اس مثال سے آپ کی طرح فائدہ اٹھائیں؟ مولوی
صاحب! اگر یہ مثال درست ہے تو اس سے تو یہ بھی لازم آتا ہے کہ کسی غیر مذہب کے آدمی کو
اپنے مذہب میں داخل نہ کیا جاوے کیونکہ وہ تو ایک دوسرے آقا کا ملازم ہے.ہمیں حق نہیں
کہ ہم اس کو اپنی ملازمت میں داخل کر لیں.وہ تو اپنے پہلے آقا کی ملازمت چھوڑ نہیں سکتا.کیونکہ آپ کا قاعدہ اس بات سے مانع ہے کہ کوئی شخص اپنے آقا کی ملازمت کو چھوڑ سکے.امید ہے کہ اس وقت تک مولوی صاحب پر یہ امر بخوبی واضح ہو گیا ہو گا کہ ان کی
پیش کردہ دلیل بالکل لغو اور لچر ہے اور وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ اگر کوئی شخص ایک دفعہ ایک
دین کو قبول کر لے تو وہ اس دین کو ترک کرنے کے معاملہ میں اب بھی ویسا ہی آزاد ہے
جیسا کہ وہ اپنے سابقہ دین کو ترک کرنے کے لئے آزاد تھا.لیکن میں ایک اور طریق سے بھی مولوی صاحب کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں.مولوی صاحب! آپ اپنی ہی پیش کردہ مثال پر مزید غور فرماویں.کیا بادشاہان وقت
استعفا بھی منظور فرمایا کرتے ہیں یا نہیں ؟ کیا تمام مہذب سلطنتوں میں استعفا کا رواج بھی
جاری ہے یا نہیں؟ پس اگر آپ کی ہی مثال کو لیا جاوے تب بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک
شخص ایک دین کو قبول کرنے کے بعد پھر اس سے مستعفی ہو سکتا ہے.اس کو قتل کرنے کی
ضرورت نہیں.لیکن اس سے بھی بڑھ کر یہ مثال ایک لطیف سبق سکھاتی ہے اور میں
مولوی صاحب کا ممنون ہوں کہ انہوں نے اس مثال کو پیش کیا.دراصل اگر مولوی صاحب
اسی اپنی پیش کردہ مثال پر غور فرماویں تو یہی اکیلی مثال ان کی ہدایت کے لئے کافی ہے.میں مولوی صاحب کی ہی مثال کو لے کر مولوی صاحب سے ایک سوال کرتا ہوں اور اس کا
جواب ان سے مانگتا ہوں.مولوی صاحب مجھے بتائیں! ایک شخص بادشاہ وقت کی
Page 119
116
ملازمت میں داخل ہوتا ہے لیکن بعد میں ثابت ہوتا ہے کہ یہ شخص اپنے فرائض کے ادا
کرنے کے نا قابل ہے.نہ یہ اپنے کام کو خوبی سے ادا کر سکتا ہے نہ اس
پر اعتماد کیا جا سکتا
ہے اور نہ یہ دل سے سرکار کا خیر خواہ ہے.اب مولوی صاحب بتائیں ! ایسے شخص کی نسبت
بادشاہ وقت کیا کارروائی کرے گا؟ کیا وہ ایسے ذرائع اختیار کرے گا کہ ایسا شخص کبھی اس کی
ملا زمت سے الگ نہ ہو یا فوراً اس کو اپنی ملازمت سے الگ کر دے گا؟ میں یقین کرتا ہوں
که مولوی صاحب یہی جواب دیں گے کہ ایسا شخص اس قابل نہیں کہ بادشاہ وقت کی
ملا زمت میں رہے.ایسے شخص کوفور علیحدہ کر دینا چاہئیے.اب مولوی صاحب اپنے اصول کو دیکھیں وہ فرماتے ہیں کہ ہم کسی کو جبراً اسلام
میں داخل نہیں کریں گے اور اس صورت میں لا إِكْرَاهَ فِی الدِّینِ پر
عمل کیا جائے گا.لیکن جب ایک شخص ایک دفعہ اسلام کو قبول کر چکے تو پھر وہ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ کے دائرہ
سے خارج ہو جاتا ہے.ایسے شخص کو جبراً اسلام میں رکھا جائے گا اور اس کو اجازت نہیں دی
جائے گی کہ وہ اسلام کو ترک کرے.اب میں مولوی صاحب کی مثال کو لے کر مولوی
صاحب سے پوچھتا ہوں کہ کیا ایسا شخص اس ملازم کی طرح نہ ہو گا جو دل سے سرکار کا
خیر خواہ نہیں ہے جو اس قابل نہیں کہ اس پر اعتماد کیا جاوے اور نہ وہ اس قابل ہے کہ اپنے
فرائض کو خوبی کے ساتھ انجام دے سکے.وہ کون سی خوبی ہے جو ہمارا بادشاہ اپنے بندوں
سے چاہتا ہے.کیا وہ یہی نہیں
قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ) (الزمر: 12)
(اے رسول) تو کہہ دے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی اس طرح عبادت کروں
که اطاعت صرف اسی کے لئے مخصوص کر دوں.پس کیا ایسا شخص اس خدمت کو بخوبی ادا کر سکے گا؟ کیا وہ اس قابل ہو گا کہ اخلاص
کا خراج اپنے بادشاہ کے حضور پیش کرے؟ ہرگز نہیں.پھر کیا وجہ ہے کہ ایسے شخص کو جبراً
Page 120
117
اسلام میں رکھا جاوے؟
پس مولوی صاحب کی اپنی ہی مثال مولوی صاحب کو یہ سبق سکھاتی ہے کہ قبول
اسلام کے بعد بھی ایمان کے معاملہ میں اکراہ جائز نہیں ہے.اگر ایک شخص اسلام سے
الگ ہونا چاہتا ہے تو اس کو ہونے دو.اس کو جبر کر کے اسلام میں رکھنا اسلام کی خدمت
نہیں بلکہ اسلام کو نقصان پہنچانا ہے.یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کی
جماعت منافقین کے وجود سے ہمیشہ پاک اور صاف رہے.اس موقع پر یہ امر قابل ذکر ہے کہ قتل مرتد کے دعویداروں نے جس قدر دلائل
قتل مرتد کی تائید میں پیش کئے ہیں ان سب میں یہ خوبی پائی جاتی ہے کہ وہ اس زور کے
ساتھ دیگر مذہب کے پیروؤں کی طرف سے بھی پیش کئے جاسکتے ہیں اور ان کی بناء پر ہر
ایک مذہب کے پیرو کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ہمارے مذہب کو چھوڑ کر اسلام قبول
کرے گا تو ہم پر واجب اور لازم ہے کہ ہم ایسے شخص کو قتل کر دیں.مولوی صاحبان اپنے زعم میں اس امر کا ثبوت دیتے ہیں کہ اسلام میں مرتد کا قتل
کرنا واجب ہے مگر وہ اس امر کو بھول جاتے ہیں کہ جو دلائل وہ پیش کر رہے ہیں وہ جیسے
مسلمانوں کی طرف سے پیش کئے جاسکتے ہیں اسی طرح مسیحیوں اور ہندوؤں کی طرف سے
بھی پیش کئے جاسکتے ہیں اور اگر مسلمانوں کا حق ہے کہ وہ اسلام سے ارتداد اختیار کرنے
والے کو قتل کر دیں تو اسی طرح مسیحیوں اور ہندوؤں کا بھی حق ہے کہ وہ تمام ان لوگوں
کو قتل
کر دیں جو ان میں سے اسلام کو قبول کریں.اس سے بھی بدتر بات یہ ہے کہ ان مولوی صاحبان کے دلائل اگر صحیح تسلیم کئے
جاویں تو ان سے ان کفار مکہ کی بھی تائید ہوتی ہے جنہوں نے ان لوگوں
کو قتل کیا جو ان میں
سے نکل کر اسلام قبول کرتے تھے اور جن کے دست تعدی کو روکنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے
رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو تلوار اٹھانے کا حکم دیا.اگر یہ دلائل درست ہیں تو نہ صرف
Page 121
118
مکہ کے صنادید مسلمانوں کو دکھ دینے میں حق پر تھے بلکہ یروشلم کے فریسی اور فقیہ اور نمرود اور
فرعون اور وہ تمام لوگ حق پر تھے جنہوں نے اپنے اپنے زمانہ میں آبائی دین ترک کرنے
والوں کو دکھ دیا اور طرح طرح کی اذیتیں پہنچا ئیں.کیونکہ جو دلائل آج ریاست کابل کے
امیر اور علماء کے فعل کی تائید میں پیش کئے جاتے ہیں وہی دلائل یہ لوگ اپنی تائید میں پیش
کر سکتے تھے اور یہی امران دلائل کے غلط ہونے کے لئے کافی دلیل ہے کیونکہ ان سے
ایسے افعال کی تائید ہوتی ہے جن کو اللہ تعالیٰ اپنی پاک کتاب میں ظلم اور تعدی قرار دے
چکا ہے.کیا قتل مرتد اسلام کو بے حرمتی سے بچانے کیلئے ضروری ہے؟
ایک اور دلیل جو قتل مرتد کی تائید میں پیش کی گئی یہ ہے کہ اسلام کو بے حرمتی سے
بچانے کے لئے مرتد کا قتل کرنا ضروری ہے.مولوی ظفر علی خان صاحب لکھتے ہیں.از برائے خدا مجھے بتائیں کہ آخر اس قانون کو جس کا نام اسلام ہے بے حرمتی
سے بچانے کے لئے واضع قانون کو کسی تدبیر کے اختیار کرنے کا حق بھی حاصل ہے یا
سے
نہیں؟
میں مولوی صاحب سے پوچھتا ہوں کہ اگر ایک غیر مذہب کا شخص انہی کے الفاظ
میں ان سے یہی سوال کرے تو وہ اس کو کیا جواب دیں گے؟ ایک سناتن دھرمی راجہ اپنے
ملک میں یہ قانون جاری کرتا ہے کہ جو شخص اس کی رعایا میں سے مسیحیت یا اسلام کو قبول
کرے تو اس کو قتل کیا جائے اور اس کی تائید میں یہی دلیل پیش کرتا ہے کہ میں اپنے دھرم کا
محافظ ہوں اور میرا فرض ہے کہ جو شخص اس مذہب کو ترک کر کے اس کی بے حرمتی کرتا ہے
میں اس کو سزا دوں اور اس طرح اپنے دھرم کو بے حرمتی سے بچاؤں.کیا مولوی صاحب
اس کے اس فعل کو اس دلیل کی وجہ سے جائز قرار دیں گے؟ مولوی صاحب! آپ ایسے
Page 122
119
دلائل کیوں دیتے ہیں جن سے ظلم کی حمایت ہو.اس سے صاف ظاہر ہے کہ آپ ایک غلط
عقیدہ کی تائید کر رہے ہیں.اسی وجہ سے جو دلائل آپ اس کی حمایت میں پیش فرماتے ہیں
لازماً اس سے باطل کی حمایت پیدا ہوتی ہے.نیز آپ نے اپنی دلیل میں بے حرمتی کا لفظ غلط طور پر استعمال کیا ہے.اگر ایک
شخص ایک مذہب کا پابند ہونے کا مدعی ہو اور اس کے تمام احکام کو درست مانتا ہو پھر وہ اس
کے قوانین کی عمد اخلاف ورزی کرے تب کہا جائے گا کہ اس نے اس قانون کی بے حرمتی
کی ہے.جب تک وہ ایک مذہب کے پیروکار ہونے کا مدعی ہے اس پر لازم ہے کہ وہ اس
کے قوانین کا احترام کرے اور خلاف ورزی کی صورت میں وہ اس بات کا مستحق ہے کہ اس
پر مقررہ حدود جاری کی جاویں.لیکن اگر وہ اس مذہب کو ترک کر کے کوئی اور مذہب اختیار
کرتا ہے تو وہ اس فعل کے ساتھ ہی اس مذہب کے دائرہ عمل سے خارج ہو جاتا ہے.اس
کی ایسی مثال ہے جیسے ایک شخص ایک حکومت سے نکل کر دوسری حکومت میں چلا جاتا ہے
اور دوسری سلطنت کی رعایا میں اپنے آپ کو داخل کر دیتا ہے.اب وہ پہلی حکومت کے
قوانین کا پابند نہیں رہتا بلکہ نئی سلطنت کے قوانین اس پر نافذ ہوں گے.ہاں ایک حکومت
سے نکل کر دوسری حکومت کی رعایا بننے کے لئے نقل مکانی کی ضرورت ہے.مگر ایک دین
سے دوسرے دین میں جانے کے لئے کسی نقل مکان کی ضرورت نہیں.صرف زبان کا
اعلان اس کو ایک مذہب سے دوسرے مذہب کی طرف منتقل کرنے کے لئے کافی ہے.ایک مذہب سے دوسرے مذہب میں داخل ہونے کے لئے کسی سفر کی ضرورت نہیں کیونکہ
مذاہب جغرافیہ کی حدود سے بالا ہیں.ظاہری سلطنتیں جغرافیہ حدود کے ذریعہ سے ایک
دوسرے سے جدا ہیں اور ایک سلطنت سے دوسری سلطنت میں جانے کے لئے ضروری
ہے کہ اُن کی حدود کو طے کیا جاوے.لیکن مذاہب کی حکومتوں کو جغرافیہ کی حدود ایک
دوسرے سے جدا نہیں کرتیں.دل کی تبدیلی سے انسان ایک مذہب سے دوسرے مذہب
Page 123
120
کی طرف چلا جاتا ہے اور زبان اس تبدیلی کا اعلان کرتی ہے.اس کے بعد اب وہ اس
شخص کی طرح ہو جاتا ہے جو ایک حکومت سے نکل کر دوسری حکومت کی ماتحتی اختیار کرتا ہے
اس لئے وہ اپنے سابق مذہب کی حکومت سے باہر چلا جاتا ہے اس لئے اس مذہب کی
حدود کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوسکتا.مولوی ظفر علی خان صاحب خود ایک موقع پر اس اصل کو
تسلیم کرتے ہیں اور ایک مذہب کو چھوڑ کر دوسرا مذہب اختیار کرنا وہ ایسا ہی سمجھتے ہیں جیسا
ایک سلطنت سے نکل کر دوسری سلطنت کے ماتحت چلے جانا اور اس صورت میں وہ اس
بات کو قبول کرتے ہیں کہ پہلے مذہب کے قوانین اس پر جاری نہیں ہو سکتے.مولوی
صاحب لکھتے ہیں :."جو شخص آج افغانستان میں سکونت پذیر ہے اور افغانستان کے قوانین کا پابند
ہے اگر کل نقل مکانی کر کے ہندوستان میں چلا آئے تو اسے عدالت و قانون کے افغانی
شکنجہ میں نہ جکڑ نا چاہئیے بلکہ اس کے ساتھ وہی سلوک کرنا چاہئیے جو انگریزی رعایا کے
ساتھ ہوتا ہے.“
مولوی صاحب شاباش! آپ نے کیا ہی سچ کہا ہے! اسی اصول پر میں کہتا ہوں کہ
جو شخص ایک مذہب کے قوانین کا پابند ہے اگر کل تبدیلی مذہب کر کے دوسرے مذہب میں
چلا جائے تو اسے پہلے مذہب کے قانون کے شکنجہ میں نہ جکڑ نا چاہیے بلکہ اس کے ساتھ وہی
سلوک کرنا چاہیے جو دوسرے مذہب کے پیروؤں کے ساتھ ہوتا ہے.پس اگر کوئی مسلمان
ہندو یا عیسائی بن جائے تو آپ کے اصول ہی کے مطابق اس سے کوئی تعرض نہ کرنا چاہئیے.مرتد کس سلطنت کا باغی ہے؟
ایک اور دلیل جو قتل مرتد کی تائید میں پیش کی گئی ہے یہ ہے کہ ارتداد، اسلام سے
بغاوت کا نام ہے اور باغی کی سزا قتل ہے.اس لئے مرتد کا قتل واجب ہے.
Page 124
اقول:
121
قتل کا فتویٰ لگانے کے لئے جرم کی کیفیت کو صراحت کے ساتھ بیان کرنا چاہئیے
اور وضاحت سے اس کی تعیین کرنی چاہئے.مرتد کے لئے بغاوت کے جرم پر قتل کا فتویٰ دینے والے اپنا فتویٰ دینے سے پہلے
ہمیں یہ بتائیں کہ مرتد کس سلطنت کا باغی ہے؟ کیا مسلمانوں کی ظاہری سلطنت کا یا اسلام
کی آسمانی بادشاہت کا ؟ کیا ایک شخص محض اپنادین بدلنے سے مسلمانوں کی ظاہری سلطنت
کا باغی ہو جاتا ہے؟ کیا دوسرے دین کی پیروی بغاوت کو مستلزم ہے؟ ریاست کابل کی
نسبت ہمیں بتایا جاتا ہے کہ وہاں مسلمانوں کے علاوہ کئی دیگر مذاہب کے پیرو بھی کثرت
سے آباد ہیں اور وہ سب امیر کا بل کی رعایا ہیں اور امن سے زندگی بسر کر رہے ہیں.اب
اگر ایک شخص ارتداد اختیار کر کے ہندو یا سکھ یا عیسائی ہو جاتا ہے تو اس کا یہ فعل مسلمانوں کی
ظاہری سلطنت کے خلاف بغاوت کیونکر کہلا سکتا ہے؟ کیا رعایا کے ایک گروہ سے نکل کر
دوسرے گروہ میں شامل ہو جانا بغاوت کہلاتا ہے.اس نے ظاہری سلطنت کے خلاف کون سا
بغاوت کا جھنڈا کھڑا کیا ہے.ہاں یہ سچ ہے کہ وہ اسلام کی آسمانی بادشاہت کا ضرور باغی ہے
مگر آسمانی بادشاہت کے باغیوں کو آسمانی بادشاہ خود سزا دیتا ہے.اس امر میں وہ ہمارا محتاج
نہیں.اس کے لئے اس نے الگ انتظام کیا ہوا ہے.وہ خدمت گزاروں کو انعام دیتا ہے اور
باغیوں کو سزا دیتا ہے.وفادار رعیت کو قرب کا انعام بخشتا ہے اور جنت کی نعمتیں عطا فرماتا ہے
لیکن باغیوں
کو جہنم کی آگ میں پھینکتا ہے.اسی لئے وہ مرتدین کی نسبت فرماتا ہے:.وَمَنْ يَرْتَدِدَ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَمَتْ وَهُوَ كَافِرُ فَأُولَبِكَ حَبِطَتْ
اعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ وَأُولَيكَ أصْحَبُ النَّارِ هُمْ
فيهَا خُلِدُونَ (البقرة: 218)
Page 125
122
اور تم میں سے جو بھی اپنے دین سے پھر جائے اور پھر کفر کی حالت میں ہی مرجائے تو یاد
رکھے کہ ایسے لوگوں کے اعمال اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اکارت جائیں گے
اور ایسے لوگ دوزخ کی آگ میں پڑنے والے ہیں.وہ اس میں دیر تک رہیں گے.پس مرتد ہماری ظاہری سلطنت کے باغی نہیں بلکہ وہ آسمانی بادشاہت کے باغی
ہیں.ایسے باغیوں سے ظاہری سلطنت کو کوئی سروکار نہیں.ان کا معاملہ خدا کے ہاتھ میں
ہے وہ خود ہی ان سے نپٹ لے گا.ہمارے سپر دصرف انہی امور کا انتظام ہے جن کا تعلق
تمدن سے ہے.پھر میں کہتا ہوں کہ صرف مرتد ہی اسلام سے باغی نہیں بلکہ ہر ایک ایسا شخص جو
اسلام کو قبول نہیں کرتا اسلام سے باغی ہے.اسلام کی سلطنت صرف ان لوگوں تک محدود
نہیں جو اس کو قبول کرتے ہیں بلکہ اس کے حدود روئے زمین کے کناروں تک پھیلے ہوئے
ہیں.جن وانس سب اس کی رعایا میں داخل ہیں اور تمام دنیا کی قومیں اس بات کی پابند
ہیں کہ اس کے آگے سرتسلیم خم کریں.کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک قوم یا ایک
ملک یا ایک زمانہ کے لئے نہیں بلکہ تمام قوموں اور تمام ملکوں اور تمام آنے والے زمانوں
کے لئے بنا کر بھیجے گئے ہیں.آپ کی دعوت تمام دنیا کی طرف ہے اور آپ کی کتاب کل
عالم کے لئے نازل ہوئی ہے اور آپ کا دین روئے زمین کے ہر فرد و بشر کے لئے قائم کیا
گیا ہے.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:.وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا (سبا:29)
اور (اے رسول) ہم نے تجھ کو تمام بنی نوع انسان کی طرف جن میں سے ایک بھی
تیرے حلقہ رسالت سے باہر نہ رہے ایسا رسول بنا کر بھیجا ہے جو مومنوں کو خوشخبری دیتا
اور کافروں کو ہوشیار کرتا ہے.پھر فرماتا ہے:.
Page 126
123
قُلْ يَا يُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيْعًا (الاعراف: 159)
(اے پیغمبر ) کہو کہ اے لوگو! میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں.جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کل دنیا کے لئے مبعوث ہوئے تو دنیا کی تمام
قوموں کا فرض ہے کہ وہ آپ کو قبول کریں اور جن قوموں نے قبول نہیں کیا وہ بھی اسلام
سے ایسے باغی ہیں جیسے مرتد باغی ہیں.پس اگر اسلام سے بغاوت کی سزا قتل ہے تو دنیا کے
تمام کفار کو قتل کرنا چاہئیے نہ صرف مرتدین کو.مرتدین میں اور دوسرے کفار میں صرف اتنا
ہی فرق ہے کہ مرتدین نے ایک دفعہ اطاعت قبول کر کے پھر سرکشی اختیار کی اور دوسرے
کفار ابتداء ہی سے سرکش رہے اور اطاعت سے سرے سے ہی انکار کر دیا.پس اگر کسی
ظاہری سلطنت کی طرف سے ایسے سرکشوں کی سرکوبی کی ضرورت ہوتی تو نہ صرف مرتدین
اس سرکوبی کے مستحق تھے بلکہ تمام کفار کی سرکوبی ضروری تھی.مگر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں نہ
کفر کی سزا مقررفرمائی ہے نہ ارتداد کی بلکہ دونوں کی سزا کے لئے آخرت میں جہنم تیار کیا گیا
ہے.اس دنیا میں کفار اور مرتدین ہر دو کو صرف اس صورت میں سزا دی جائے گی جب وہ
اسلامی سلطنت کا مقابلہ کریں یا اسلامی سلطنت کی حدود میں فساد کے مرتکب ہوں ورنہ محض
کفر یا ارتداد کے لئے اس دنیا میں کوئی سزا مقرر نہیں.دونو کے لئے اللہ تعالیٰ صرف
آخرت کی سزا بیان فرماتا ہے اور بس.اگر صرف مرتد کو قتل کیا جاوے اور باقی کفار سے کوئی
تعرض نہ کیا جاوے تو اس سے یہ سمجھا جائے گا کہ چونکہ مرتد اکا دُکا مسلمانوں کے قابو میں
ہوتا ہے اس لئے اس کو تو قتل کر دیتے ہیں اور باقی کفار چونکہ ایک جمعیت رکھتے ہیں اور ان
کو قتل کرنا آسان
کام نہیں اس لئے ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے.آزادی ضمیر اور کابل کی سنگساریاں
آزادی ضمیر کے اصول پر جرح کرتے ہوئے حامیان
قتل مرتد نے ایک اعتراض
Page 127
124
یہ کیا ہے کہ اگر آزادی ضمیر کا پیش کردہ اصول درست ہے تو کابل کی سنگساریوں پر کوئی
اعتراض نہیں ہوسکتا.ایک مولوی صاحب فرماتے ہیں:.جن لوگوں کی آزادی تعمیر قتل مرتد کا فتوی دے رہی ہے وہ اپنی آزادی کی نمائش
کے لئے کہاں جائیں؟ اگر آزادی ضمیر کا مطلب یہی ہے کہ ہر شخص جو چاہے کہے
اور جو چاہے کرے تو پھر افغانستان کے ان لاکھوں باشندوں پر کیوں اعتراض کیا
جاتا ہے جو نہ دل سے قتل مرتد کے معتقد ہیں؟ کیا ان پر اعتراض ان کی آزادی ضمیر
سے تعرض نہیں ہے؟“
پیشتر اس کے کہ مولوی صاحب کے سوال کا جواب دوں، میں ان سے پوچھتا
ہوں کہ آزادی ضمیر کے وہ معنے کس نے کئے جن کی بنا پر آپ اعتراض کر رہے ہیں.کس
نے کہا کہ آزادی ضمیر کے یہ معنے ہیں کہ ہر شخص جو چاہے کہے جو چاہے کرے؟ اگر حامیان
عدم مقتل مرتد نے ایسا نہیں لکھا تو دنیا کی کسی اور قوم کا نام لوجو آزادی ضمیر کے یہ معنے کرتی ہو
جو آپ نے اس کی طرف منسوب کر کے ان پر اعتراض قائم کرنے شروع کر دئے ہیں.عدم قتل مرتد کے قائلین کا تو اس سے زیادہ کوئی دعوی نہیں کہ اختلاف عقائد کی
خاطر یا محض کفر یا ارتداد کی وجہ سے سزا نہیں دینی چاہئیے.میں اس امر کی اوپر تشریح کر چکا
ہوں اس لئے اعادہ کی ضرورت نہیں.آزادی ضمیر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس کو چاہے قتل
کرے.جس کو چاہے ذلیل کرے.جس کا چاہے مال چھین لے.جس کا چاہے حق دبا
لے.دیکھو سلطنت برطانیہ نے اپنی رعایا کو مذہبی آزادی دے رکھی ہے مگر باوجود اس مذہبی
آزادی کے وہ کسی ہندو عورت کو اجازت نہیں دیتی کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ ستی ہو
جاوے.نہ کسی ہندو کو یہ اجازت دیتی ہے کہ وہ کسی انسان کی قربانی کرے کیونکہ اس کا اثر
تمدن پر اور دوسروں کے حقوق پر پڑتا ہے اور آزادی ضمیر کا یہ منشا نہیں کہ انسان اپنے خیال
کے مطابق لوگوں کے حقوق بھی دبا لے.پس اگر افغانستان کی آبادی یہ عقیدہ رکھتی ہے کہ
Page 128
125
مرتد کو قتل کرنا واجب ہے تو یہ عقیدہ ان کو مبارک ہو لیکن ان کو یہ آزادی حاصل نہیں ہے کہ
وہ اپنے عقیدہ کو اس طور پر عملی جامہ پہنائیں کہ دوسرے لوگوں کے جان و مال اور عزت کا
نقصان کریں.مولوی صاحب! افغانستان کی آبادی کا تو یہ بھی عقیدہ ہوگا کہ ایک انگریز کا فر کا قتل
کرنا انسان کو سیدھا جنت میں لے جاتا ہے.چنانچہ بعض اوقات خود انگریزی علاقہ میں
بعض افغانوں نے اپنے اس عقیدہ کے مطابق بے گناہ انگریز عورتوں اور مردوں کو قتل
کر کے بہشت حاصل کرنے کی کوشش بھی کی ہے.اب مولوی صاحب فرما دیں کہ اگر ایک
افغان ایک انگریز کو صرف اس کے کفر کی وجہ سے اس لئے قتل کر دے کہ وہ تہ دل سے اس
امر کا معتقد ہے کہ ایک انگریز کا فر کا قتل انسان کو جنت میں پہنچا دیتا ہے تو کیا مولوی
صاحب انگریزی عدالت میں اس کی طرف سے وکالت کرتے ہوئے یہ دلیل پیش کریں
گے کہ انگریزی سلطنت آزادی ضمیر کے اصول کو صحیح تسلیم کرتی ہے اس لئے وہ ایک افغان
کے اس فعل کو محل اعتراض قرار نہیں دے سکتی.آخر جن لوگوں کی آزادی ضمیر اس امر کا فتویٰ
دیتی ہے کہ ایک انگریز کافر کو قتل کرنا کار ثواب ہے وہ اگر انگریزوں
کو قتل نہ کریں تو اپنی
آزادی ضمیر کی نمائش کے لئے کہاں جائیں.کیا ایسی دلیل پیش کرنے پر حج مولوی صاحب
کی اس دلیل کو ان کے خلل دماغ کی طرف منسوب کر کے ان کو پاگل خانہ میں نہیں بھیج
دے گا؟
کیا مولوی صاحب ایک ہندو کو یہ ترغیب دے سکتے ہیں کہ تم بے شک اپنے عقیدہ
کے مطابق انسانی قربانی کی رسم ادا کرو میں تمہاری طرف سے جھگڑوں گا کہ ایسے شخص کو سزا
دینا مذ ہبی آزدی کا چھینا ہے.کیا مولوی صاحب ایک ہندو بیوہ کو جس کا خاوند ا بھی مرا ہے
اور اس کی لاش مرگھٹ کی طرف اٹھا کر لے جارہے ہیں یہ تلقین کریں گے کہ تو ضرور اپنے
خاوند کی چتا میں کود کرستی کی رسم ادا کر.اگر کوئی تجھے روکے گا تو میں تیری طرف سے پریوی
Page 129
126
کونسل تک لڑوں گا کہ ایک ہندو استری کوستی کی مقدس رسم کے ذریعہ اپنی وفا داری اور جان
شاری کا ثبوت دینے سے روکنا مذ ہبی امور میں دخل اندازی ہے جو ملکہ وکٹوریہ کے شاہی
اعلان کے بالکل خلاف ہے.میں پھر مولوی صاحب کو یاد دلاتا ہوں کہ جس آزادی ضمیر کی قرآن شریف تعلیم دیتا
ہے اور جس کی صحت کو تمام مہذب دنیا تسلیم کرتی ہے اس کا صرف یہی مطلب ہے کہ اگر
ایک شخص کوئی خاص عقیدہ رکھتا ہے تو محض اس کے عقیدہ کی بنا پر اس کو سزا نہیں دینی چاہئیے
اور نہ اس پر کسی طرح کا جبر کرنا چاہیے.اسی طرح اس عقیدہ کی بناء پر اگر وہ کوئی ایسا کام کرتا
ہے جس کا اثر صرف اس کی ذات تک محدود ہے دوسروں کے مال و جان وعزت پر اس کا
کوئی اثر نہیں تو ایسے فعل کے لئے بھی ہمیں اسے کسی قسم کی سزا دینے سے اجتناب کرنا
چاہئیے.ہاں
سمجھانا ہمارا فرض ہے اگر وہ سمجھے تو آخر الحیل السیف پر عمل نہیں کرنا چاہئیے
کیونکہ اس کا معاملہ خدا کے سپرد ہے.خدا تعالیٰ خود اس سے پوچھ لے گا.کسی عقیدہ کی وجہ
سے سزا دینا ہمارا کام نہیں.حکومت صرف اسی وقت دخل دے سکتی ہے جب وہ لوگوں کے
مال یا جان یا عزت یا دوسروں کے حقوق پر حملہ کرے اور تمدن دنیا میں خلل انداز ہو.قتل مرتد اور حفاظت اسلام
مولوی شبیر احمد صاحب دیو بندی قتل مرتد کی تائید میں ایک بڑی بھاری دلیل یہ
دیتے ہیں کہ حفاظت اسلام میں اس میں بڑی مدد ملے گی.قتل مرتد کے جواز یا وجوب کی
صورت میں یہ اعتراض کیا گیا ہے کہ اگر مسلمان حکومتیں یہ قانون بنائیں کہ جو شخص اسلام
میں سے نکل کر کوئی غیر مذہب مثلاً مسیحیت و غیر ہا کو قبول کرے گا تو اس
کو قتل کیا جائے گا.اور اس بناء پر یہ قاعدہ بھی جاری کریں کہ غیر مسلموں کو ان کے ملک میں اپنے مذہب کی تبلیغ
کرنے کی اجازت نہیں تو اسکا نتیجہ یہ ہوگا کہ غیر مسلم سلطنتیں بھی اسلام کے خلاف ایسا ہی
Page 130
127
قانون جاری کریں گی اور اسلام کی اشاعت کا کام بند ہو جائے گا.66
اس اعتراض کے جواب میں مولوی صاحب فرماتے ہیں کہ اول تو اگر وہ ایسا
کریں گے تو ہم ان کو حق بجانب نہیں کہہ سکتے کیونکہ ان کا مذہب جھوٹا ہے اور ہمارا سچا.تاہم یہ ضرور ہے کہ وہ ایسا کر گزریں تو ہم ان کو روک بھی نہیں سکتے.نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک
طرف اگر نو مسلموں کا سلسلہ رک جائے گا تو دوسری جانب پرانے مسلمانوں کا اسلام سے
نکلنا بھی بند ہو جائے گا اور میں خیال کرتا ہوں کہ موجودہ دولت کی حفاظت غیر موجود دولت
کی تحصیل سے اہم اور مقدم ہے.“
معلوم ہوتا ہے مولوی صاحب نے یہ سبق ہندوؤں سے سیکھا ہے.ہندوؤں کو
چونکہ اپنی کمزوری کا علم ہے اس لئے ان کو یہ تو امید نہیں تھی کہ میدان میں نکل کر کسی
توحید پرست مذہب پر فتح پالیں گے اس لئے انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا کہ کسی غیر کو اپنے
مذہب میں داخل ہی نہ کیا جاوے اور اپنی موجودہ دولت کی ہر طرح حفاظت کی جاوے اور
اسی غرض کے حاصل کرنے کے لئے انہوں نے چھوت چھات وغیرہ کے قواعد جاری کر
دئے تا کسی طرح ہماری حاصل شدہ دولت ہمارے ہاتھ سے نہ نکل جائے.مگر اسلام ہندو
مذہب کی طرح نہیں ہے وہ ایک فاتح مذہب ہے اس کے ہاتھ میں سچائی کی تلوار ہے اور
کسی میں طاقت نہیں کہ اس کے سامنے ٹھہر سکے.اس کو اس امر کی ضرورت نہیں کہ وہ اس
خوف سے کہ کہیں اس کی دولت چھینی نہ جائے اپنے گھر کے دروازے غیروں پر بند کر
دے.اس کو اس امر کی ضرورت نہیں کہ وہ غیر مذاہب کے مشنریوں سے اپنی دولت
بچانے کے لئے اپنے گھر کے دروازے بند کر دے اور اپنی چار دیواری کے اندر محصور ہوکر
بیٹھ جائے.یہ تو کمزوری کی علامت ہے.اس کے ہاتھ میں ایک تلوار ہے جس کے سامنے
ایک تثلیث پرست مشنری ایک لمحہ کے لئے ٹھہر نہیں سکتا.پھر اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ
ایسا طریق اختیار کرے جس کا نتیجہ یہ ہو کہ اس کی فتوحات کا سلسلہ ہمیشہ کے لئے بند ہو
Page 131
128
جائے.وہ جو دلائل کے ساتھ غیر ممالک کو فتح کر سکتا ہے اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ اپنے
ارد گرد چاردیواری کھینچ کر گھر میں محفوظ ہو کر بیٹھ جائے.وہ گھر سے باہر نکلے گا اور دشمنوں کو
شکست پر شکست دے گا اور نئے ممالک
کی تسخیر کر کے اپنے علاقہ کو وسعت دے گا.اور
اگر اس کے علاقہ پر کوئی دشمن حملہ آور ہو گا تو وہ اسی دلائل کی تلوار سے اس کو بھی شکست دے
گا.وہ قلعہ جس میں اسلام محفوظ ہے وہ دلائل اور سچائی کا قلعہ ہے.اس کو اپنی حفاظت کے
لئے ایسی کچی دیواروں کی ضرورت نہیں جس کو دشمن اپنے ظاہری بازو کی طاقت سے توڑ
سکے.یہ دیوار جو مولوی صاحب اسلام کے گرد کھینچنا چاہتے ہیں یعنی غیر مذاہب کے
مشنریوں کو اسلامی علاقوں میں داخل ہونے سے روک دینا یہ تو نہایت ہی بودی دیوار ہے
جس کو دشمن اپنے ظاہری بازو کی قوت سے توڑ سکتا ہے بلکہ یہ دیوار تو اس سے قبل ہی ٹوٹ
چکی ہے.اگر اسی دیوار پر اسلام کی حفاظت کا دارو مدار تھا تو اب اسلام کی خیر نہیں کیونکہ یہ
دیوار تو ہر طرف سے ٹوٹی ہوئی نظر آتی ہے.یہ تو زمین سے پیوست ہو چکی ہے.یہ تو اسلام
کی دولت کو نہیں بچا سکتی.ہندوستان میں کئی کروڑ مسلمان ہیں اب ہندوستان کی دولت کو
مولوی صاحب کس طرح دیوار کے ذریعہ بچائیں گے؟ کیا مولوی صاحب کے ہاتھ میں
طاقت ہے کہ ہندوستان کے ارد گرد کوئی ایسی دیوار کھینچیں کہ ہندوستان کی حدود کے اندر
کوئی مشنری گھنے نہ پائے؟ کیا مولوی صاحب کے ہاتھ میں کوئی ایسی تلوار ہے جس کے
زور سے وہ ان مشنریوں کی فوجوں کو جو اس وقت ہندوستان میں غارت گری میں مصروف
ہیں ہندوستان سے باہر نکال سکیں ؟ کیا ایران کے اردگرد یا مصر کے حدود پر یا شام کے
ساحل پر یا عراق کے کناروں پر یا خود استنبول میں جو خلیفتہ المسلمین' کا تخت گاہ رہ چکا
ہے
مولوی صاحب کوئی ایسی سید سکندری کھڑی کر سکتے ہیں کہ مسیحی مشنری ان علاقوں میں گھس
نہ سکے اور اس طرح ہماری موجودہ دولت محفوظ رہ سکے؟ مولوی صاحب ! اگر یہی دیوار تھی
جو آپ کی دولت کی محافظ تھی تو یہ دیوار تو اب مسمار ہو کر خاک سے مل چکی ہے.اب آپ
Page 132
129
اپنی دولت کو کہاں چھپائیں گے.کیا صرف افغانستان کی چاردیواری کے اندر تمام اسلامی
دنیا پناہ لے سکتی ہے؟ مولوی صاحب آپ کو معلوم ہونا چاہئیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی
حفاظت کا انحصار ان دیواروں پر نہیں رکھا بلکہ وہ دیوار جس کے اندر اسلام محفوظ ہے وہ
صداقت کی دیوار ہے جس کو کوئی نیم تو نہیں سکتا.اسلام کی حفاظت کے لئے کسی ظاہری
تلوار کی ضرورت نہیں.اسلام امیر امان اللہ خان کی تلوار کا محتاج نہیں.یہ لوگ تو خود اپنے
تیں دشمنوں سے بچا نہیں سکتے یہ اسلام کو کیا بچا ئیں گے.اسلام کا محافظ خود اس کی اپنی
سچائی ہے مگر مولوی صاحبان خود اس نور سے محروم ہیں.ان کو اس طاقت کا علم نہیں جو اسلام
میں پائی جاتی ہے.اس لئے ان کی نظر پھر پھرا کر آخر تلوار پر ہی جاپڑتی ہے اور انہوں نے
تلوار کو ہی اسلام کا محافظ سمجھ رکھا ہے.مولوی صاحب کا یہ کہنا کہ اگر اشاعت اسلام رکتی ہے تو رُکنے دو.موجودہ دولت
کی حفاظت مقدم ہے.اس لئے ہم غیر مذاہب کے مبلغین کو اسلامی ملکوں میں گھنے نہیں
دیں گے ایک اور لحاظ سے بھی غلط ٹھہرتا ہے.اسلام تمام دنیا کیلئے ہے اور جیسا ہمارا یہ فرض
ہے کہ ہم موجودہ دولت کی حفاظت کریں اسی طرح ہمارا یہ بھی فرض ہے کہ بیرونی دنیا میں
بھی اسلام کی تبلیغ کریں.اس لئے کوئی ایسا حکم اسلامی حکم نہیں کہلا سکتا جس کا نتیجہ یہ ہو کہ
بیرونی دنیا میں اشاعت اسلام کا سلسلہ بند ہو جاوے.یہ کس طرح ممکن ہے کہ ایک طرف
اسلام ہمیں یہ حکم دے کہ تمام دنیا میں تبلیغ اسلام کرو اور دوسری طرف ایسا حکم دے جس کا
لازمی نتیجہ یہ ہو کہ تبلیغ اسلام کا سلسلہ رک جائے.لیکن اگر مولوی صاحب کے مشورہ پر عمل
کیا جاوے تو اس کا ضروری نتیجہ یہ ہوگا کہ نہ صرف اسلام آئندہ ترقی کرنے سے رُک
جائے گا بلکہ مسلمانوں کی موجودہ تعداد بھی ہندوؤں کی طرح روز بروز گھٹتی جائے گی اور اگر
مولوی صاحبان کے فتاوی کفر وقتل مرتد پر پورے طور پر عمل کیا گیا تو مسلمان بہت جلدی
دنیا سے مٹ جائیں گے.کیونکہ ایک طرف تو ترقی رکی ہوئی ہوگی اور دوسری طرف علماء کی
Page 133
130
طرف سے زندیق اور کافر بنانے کا سلسلہ جاری رہ کر (جیسا کہ تجربہ سے ثابت ہو چکا ہے)
مسلمانوں کی رہی سہی تعداد کو بھی کم کرتا جائے گا.آؤ مولوی صاحب! میں آپ کو سمجھاؤں کہ اسلام کی حفاظت کا حقیقی ذریعہ کیا ہے
جس کے اختیار کرنے سے آپ اس بات پر مجبور نہیں ہوں گے کہ اسلام کی تبلیغ کرنا چھوڑ
بیٹھیں.مسلمانوں کو سچے مسلمان بناؤ.غیر مذاہب کے مشنریوں کا لوہے کی تلوار سے نہیں
بلکہ اسلامی صداقت کی تلوار کے ساتھ مقابلہ کرو تا وہ شکست کھا کر بھاگ جائیں اور آپ
کے سامنے اپنا منہ نہ دکھا سکیں اور پھر آپ غیر اقوام میں ہر ایک ممکن ذریعہ سے تبلیغ کریں
اور اسلام کا چمکتا ہوا چہرہ دکھائیں تا وہ اسلام پر دل و جان سے قربان ہو کر کلمہ شہادت
پڑھتے ہوئے فوج در فوج اسلام میں داخل ہوں.مگر آپ سچے ہیں آپ سے یہ کام نہیں ہو
سکتا.کیونکہ آپ خود اسلام سے دُور ہو گئے ہیں اور آپ کا اسلام وہ اسلام نہیں جو رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا.یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو دوبارہ زندہ کرنے کے
لئے اور غیر قوموں کو زندہ اسلام کا پیارا چہرہ دکھانے کے لئے مسیح موعود کو بھیجا.اب انشاء اللہ
یہ کام مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت کے ذریعہ ہوگا.وَمَا تَوْفِيْقَنَا إِلَّا بِاللَّهِ
قتل مرتد اور عقل
حامیان قتل مرتد نے یہ امر نہایت سختی کے ساتھ محسوس کیا ہے کہ قتل مرتد ایک
ایسا مسئلہ ہے جس سے فطرت انسانی کراہت کرتی ہے اور جس کو عقل سلیم دھکے دیتی ہے.جیسا کہ انہوں نے خود بھی صریح الفاظ میں تسلیم کیا ہے قتل مرتد کے یہ معنے ہیں کہ لوگوں پر
دین کے معاملہ میں پوری سختی اور شدت کے ساتھ جبر کیا جاوے اور جبر ایک ایسی چیز ہے
جس کو نہ صرف قرآن شریف ناجائز قرار دیتا ہے بلکہ عقل انسانی بھی اس کو نہایت ہی نفرت
کی نگاہ سے دیکھتی ہے اس لئے ان بزرگوں نے اپنا سارا زور لگانے اور اپنی ساری قوت
Page 134
131
خرچ کر دینے کے بعد اس امر کو اپنی ساری طاقت سے بالا پایا کہ اس کو عقلی پہلو سے
درست اور صحیح ثابت کر سکیں.سو آخر کار تھک کر خود عقل کو ہی جواب دینے کی کوشش کی.مولوی شاکر حسین صاحب سہسوانی ” شرعی احکام اور عقل“ کے عنوان کے ماتحت لکھتے
ہیں:.فاضل مضمون نگار کو استعجاب ہے کہ جب جبر کے ذریعہ سے کوئی مسلمان نہیں بنایا
جاتا تو مسلمان رکھنے کیلئے جبر کا حکم کیونکر دیا جا سکتا ہے؟ مگر اس حقیقت واقعی کو کیا کیا جائے
کہ اسلام کا صحیح اور نا فذ حکم یہی ہے اور اس میں کیونکر اور کیسے کی گنجائش نہیں.اول تو اس حکم
میں عقل سے کچھ استبعاد نہیں.اگر ہو بھی تو لازمی نہیں ہے کہ جملہ احکام شریعت پر ہمارا فلسفی و
منطقی استدلال منطبق ہو سکے.یا ہم ان کی علت دریافت کرنے کا حق رکھتے ہوں.“
مولوی ظفر علی خان صاحب اس امر کے تسلیم کرنے سے تو گریز نہیں کر سکے کہ
اسلام حق و باطل کے پر کھنے کے لئے عقل کو ایک کسوٹی قرار دیتا ہے.لیکن چونکہ وہ اپنے
دل میں خوب سمجھتے تھے کہ وہ قتل مرتد کے مسئلہ کو عقل کی کسوٹی سے پر کھ کر صحیح ثابت نہیں کر
سکتے.اس لئے عقل کی بحث میں انہوں نے پوری کوشش کی ہے کہ اس معیار سے اس مسئلہ
کو نہ جانچا جائے.مسٹر گاندھی کے اس مطالبہ کے جواب میں کہ کسی اصول موضوعہ کو عالمگیر حیثیت
سے تسلیم کرنے کیلئے ضروری ہے کہ پہلے اسے عقل کی حق و باطل کو پر کھنے والی کسوٹی پر کسا
جائے.مولوی صاحب لکھتے ہیں:.اس اصول سے کسی کو انکار نہیں ہوسکتا اور تمام ادیان و شرائع میں اسلام سب سے
پہلا مذہب ہے جس نے حق و باطل کے امتیاز کا یہ اصول پیش کیا اور اسی پر اپنی قبولیت وعدم
قبولیت کا انحصار رکھا.لیکن سوال یہ ہے کہ عقل کی حق و باطل کو پر کھنے والی کسوٹی کیا ہوگی...اگر ہر فرد کی ممسوخ عقل ہر دین و شریعت اور ہر نظام و آئین کی صحت و عدم کی کسوٹی
Page 135
132
بن جائے تو آج دین میں ایک نظام اور شریعت قائم نہ رہے.ایک بت پرست اپنے ہاتھ
سے پتھر کی مورت تراشتا ہے.پھر کیا اس بت پرست کی عقل رب المشرقین و المغر بین
کے
تسلیم و عدم تسلیم کا معیار بن سکتی ہے.ایک چور اپنے ہمسایوں کے مال ومتاع کا احترام
ملحوظ نہیں رکھتا...پھر کیا حد سرقہ کے لئے اس چور کی نادرست عقل کسوٹی بن سکتی ہے.غرض کہ اس قسم کی صد با مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں جن کی بنا پر آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ حق
و باطل کے پر کھنے والی عقل کی بھی خاص حدیں ہیں...ایک ایسی عقل کی تلاش کرنی پڑے
گی جس کے پیش نظر کا ئنات انسانیت کی فلاح و بہبود ہو.جب بنی آدم کے امن و امان اور
راحت و آسائش کی حفاظت کے فرائض کو پورے طور پر محسوس کرتی ہو اور فتنہ وفساد اور بغض
وعداوت کی شرانگیزیوں کے سدِ باب میں انسانی دماغ.انسانی ذہنیت اور انسانی جذبات
وحیات سے تجاوز نہ کرتی ہو یعنی انسانوں کو انسان جھتی ہوایسی ہی عقل کی بناء پرقتل مرتد
کے حکم کا اندازہ کرنا چاہئیے.لیکن اس باب میں حکم بنے کیلئے اس عقل کا معیار کیونکر صحیح مانا جا
سکتا ہے جو کائنات انسانیت تو ایک طرف رہی اس کے ایک ٹکڑے یعنی اہلِ ہند کے گزشتہ
چار پانچ سال کے معاملات میں خود اپنے قول کے مطابق ہمالیہ جتنی بڑی غلطیاں کر چکی
ہے.مندرجہ بالا اقتباس میں مولوی صاحب نے مسٹر گاندھی کے آگے ایک ایسی شرط
پیش کر دی ہے جس کو نہ وہ پورا کر سکیں گے اور نہ قتل مرتد کے مسئلہ کو معقولی رنگ میں درست
ثابت کرنے کی نوبت آئے گی.مولوی صاحب مسٹر گاندھی کو کہتے ہیں کہ اگر تم قتل مرتد کا
معقولی ثبوت ہم سے چاہتے ہو تو جاؤ دنیا میں پھرو، اور روئے زمین کے مشرق و مغرب میں
چکر لگاؤ اور کسی ایسی عقل کی تلاش کرو جو بنی آدم کی راحت و آسائش کے فرائض کو پورے
طور پر محسوس کرتی ہو اور بغض و عداوت کی شرانگیزیوں کے سدباب میں انسانی دماغ.انسانی ذہنیت اور انسانی جذبات و حیات سے تجاوز نہ کرتی ہو.اور پھر اس میں یہ خوبی
Page 136
133
ہو کہ اس نے تمام کائنات انسانیت کے عمر بھر کے معاملات میں کبھی غلطی نہ کی ہو.ظاہر
ہے کہ نہ مسٹر گاندھی کسی ایسی عقل کو پیش کر سکیں گے اور نہ مولوی صاحب کو اس امر کی
ضرورت پیش آئے گی کہ قتل مرتد کو معقولی رنگ میں صحیح ثابت کریں.چلو چھٹی ہوئی.نہ کو
من تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی.مولوی صاحب! اگر عقل کی حق و باطل کو پر کھنے والی کسوٹی ایسی ہی نایاب چیز ہے تو
اسلام نے خود آپ کے اقرار کے بموجب حق و باطل کے امتیاز کا یہ اصول کیوں پیش کیا اور
آپ کے بیان کے بموجب اسی پر اپنی قبولیت و عدم قبولیت کا انحصار کیوں رکھا ؟ کیا اپنی سچائی
کے جانچنے کے لئے کوئی ایسا معیار پیش کرنا جس کا حاصل ہونا ناممکنات سے ہو عمداً دنیا کو
دھوکہ دینا نہیں ہے؟ کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس معیار کو پیش کرنے والا دراصل
اپنے دعوئی میں جھوٹا ہے اور دنیا کو فریب دیتا ہے کیونکہ وہ اپنے دعوی کی صحت کو جانچنے کے
لئے ایک ایسا معیار پیش کرتا ہے جس کے ذریعہ اس کے بیان کی سچائی پر کھنا ہی ناممکن ہے.پھر میں مولوی صاحب سے پوچھتا ہوں کہ انہوں نے اور ان کے ہمنوا
مولوی صاحبان نے اسلام کو کیوں اختیار کر رکھا ہے، کیا اس لئے کہ وہ مسلمانوں کے
گھر میں پیدا ہوئے یا انہوں نے عقل کی حق و باطل کو پر کھنے والی کسوٹی سے اسلام کو
جانچ کر دیکھ لیا ہے کہ یہ سچا دین ہے؟ اگر امر اول ان کے مسلمان رہنے کی وجہ ہے تو
اس صورت میں میرا اُن سے کوئی مطالبہ نہیں.لیکن اگر انہوں نے عقل کی حق و باطل
کو پر کھنے والی کسوٹی سے اسلام کو جانچ کر دیکھ لیا ہے کہ یہ ایک سچا دین ہے تو پھر میں
ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا ان سب کی عقلوں میں وہ سب صفات موجود ہیں جو مولوی
صاحب نے تجویز فرمائے ہیں اور کیا ان کی عقلوں نے کبھی رائی برابر بھی کوئی غلطی
نہیں کھائی.اگر مولوی ظفر علی خان صاحب اور ان کے ہم خیال علماء اپنی عقل کے
ذریعہ اسلام کی صداقت کو جانچ سکتے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ دوسرے لوگ اسلام کے
Page 137
134
صرف ایک حکم کی معقولیت کو بھی اپنی عقل کے ذریعہ جانچ نہ سکیں.اصل بات یہ ہے کہ عقلی معیار سے کسی خاص انسان کی شہادت مراد نہیں بلکہ اس
کا مطلب یہ ہے کہ کسی امر کے ثبوت میں ایسے دلائل پیش کئے جاتے ہیں جو انسانی عقل
سے اپیل کرتے ہیں.ایسے دلائل اگر صحیح اور زبردست ہوں گے تو ان کا اثر ہر ایک غور
کرنے والے انسان کے دل پر ضرور پڑے گا.خواہ اس کی عقل ہمالیہ جتنی بڑی غلطیاں
کر چکی ہو.خواہ وہ چوری کا عادی ہو یا بت پرستی کی بلاء میں مبتلا ہو.یہ الگ بات ہے
کہ وہ رسم و رواج کی پابندی کی وجہ سے یا تعصب یا ضد کی وجہ سے یا کسی اور بیرونی اثر
کے ماتحت ایک امر حق کو قبول نہ کرے.لیکن ایک زبر دست اور مضبوط دلیل کو سننے اور
خالی الذہن ہو کر اس پر غور اور تدبر کرنے سے اس کا دل ضرور شہادت دے گا کہ بات تو
سچی ہے.کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت تمام عرب شرک اور بت پرستی
کے گہرے سمندر میں غرق نہیں تھا ؟ کیا عرب میں ڈاکہ مارنے والے اور انسانوں کو
بے دریغ قتل کرنے والے انسان موجود نہ تھے؟ پھر وہ کیا چیز تھی جس نے ان کے
دلوں کو فتح کر لیا اور ان کو اسلام کا عاشق اور جان نثار غلام بنا دیا؟ وہ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کی صداقت کے زبر دست دلائل ہی تھے جنہوں نے ان کے دلوں کو یقین دلایا
کہ یہ مدعی اپنے دعوی میں راستباز ہے.وہ بتوں کو پوجتے تھے.لیکن جب انہوں نے
قرآن شریف کے زبر دست دلائل کو سنا تو ان کے دلوں نے شہادت دی کہ بت بے جان
پتھروں سے زیادہ کچھ بھی حقیقت نہیں رکھتے.انہوں نے اپنے بتوں کو توڑا اور کلمہ شہادت
پڑھتے ہوئے اسلام میں داخل ہوئے.غرض جب مسٹر گاندھی نے مولوی صاحب سے عقلی معیار پر قتل مرتد کے حکم کو
جانچنے کا مطالبہ پیش کیا تھا تو اس سے ان کی یہ مراد نہ تھی کہ وہ اس کی معقولیت کے متعلق زید
یا بکر کی شہادت پیش کریں بلکہ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ وہ اس کی تائید میں ایسے دلائل پیش
Page 138
135
کریں جن سے ہر ایک غور کرنے والا انسان یہ سمجھ سکے کہ قتل مرتد ایک نہایت ہی معقول حکم
ہے.اگر ان دلائل سے مسٹر گاندھی کو کچھ فائدہ نہ ہوتا تو کم از کم دوسرے انصاف پسند اور
غور کرنے والے انسان تو مولوی صاحب کے زبر دست عقلی دلائل کو سن کر عش عش کر اٹھتے
اور اس امر کے تسلیم کرنے پر مجبور ہوتے کہ قتل مرتد واقعی ایک نہایت ہی معقول اور پسندیدہ
حکم ہے.مگر مولوی صاحب نے یہ راہ ہی اختیار نہیں کی بلکہ الٹا مسٹر گاندھی کو گالیاں دینے
پر اتر آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ
تمہاری عقل تو صرف ہندوستان کے معاملات میں ہمالیہ جتنی بڑی غلطیاں
کرنے کی عادی ہے تم کس طرح اس حکم کی معقولیت کو سمجھ سکتے ہو.کوئی ایسی عقل پیش کرو
جو تمام کائنات انسانیت کے ساتھ معاملہ رکھتی ہو اور اس نے اپنی ساری عمر میں ایک مرتبہ
بھی رائی برابر بھی غلطی نہ کی ہو.ایسی عقل اس بات کے سمجھنے کے قابل ہوگی کہ قتل مرتد ایک
نہایت ہی اعلیٰ درجہ کا حکم ہے.“
مولوی شاکر حسین صاحب سہسوانی ایڈیٹر کا مریڈ کے اس سوال کے جواب میں کہ
جب جبر کے ذریعہ کوئی مسلمان نہیں بنایا جاتا تو مسلمان رکھنے کے لئے جبر کا حکم کیوں کر دیا
جاسکتا ہے.فرماتے ہیں کہ
اس حقیقت واقعی کو کیا کیا جاوے کہ اسلام کا صحیح اور نافذ حکم یہی ہے کہ اس میں
کیونکر اور کیسے کی گنجائش نہیں ہے.“
اقول
مولوی صاحب اس بات کو بھول گئے ہیں کہ یہی امرتو متنازعہ فیہ ہے کہ آیا قتل مرتد
اسلام کا صحیح حکم ہے یا نہیں ؟ اور اس دعوی کی تائید میں کہ یہ اسلامی حکم نہیں ہے ایڈیٹر کامریڈ
نے آیت کریمہ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّینِ کو پیش کیا ہے.اب اس جرح کا یہ جواب نہیں ہو سکتا
Page 139
136
کہ چونکہ یہ اسلام کا ایک صحیح حکم ہے اس لئے ایڈیٹر صاحب کو اس پر جرح کرنے کا اختیار
نہیں.مولوی صاحب کے اس جواب سے اگر کچھ ثابت ہوتا ہے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ
مولوی صاحب فن مناظرہ سے نا آشنا ہیں.دعویٰ اور دلیل میں فرق نہیں کر سکتے اور ایک
دعوی کو بطور دلیل کے پیش کر رہے ہیں.جب ایک امر کے متعلق دو فریق میں اختلاف ہواور وہ ہر دو اس امر کے متعلق
تبادلہ خیالات کر رہے ہوں تو ایک فریق دوسرے فریق کو یہ جواب نہیں دے سکتا کہ چونکہ
یہ ایک مذہبی امر ہے اس لئے اس میں عقل کو دخل نہیں ہونا چاہیئے.اگر ایک انسان ایک
مذہب
کو علی وجہ البصیرت قبول کرتا ہے تو اس کے یہی معنے ہیں کہ اس نے عقل کی کسوٹی پر
اسے جانچ کر دیکھ لیا ہے اور اس کو درست اور صحیح پایا ہے.ہاں میں اس امر کو تسلیم کرتا ہوں
کہ جب انسان ایک مذہب کو اصولی طور پر عقلی معیار کی رو سے منجانب اللہ اور صحیح قبول کر
لیتا ہے تو پھر اس کے لئے ضروری نہیں کہ تمام تفصیلات کی بھی حکمت اس کو معلوم ہو.اس
کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اصولی طور پر ایک مذہب کو علی وجہ البصیرت سچا یقین کرتا ہے.لیکن جب اسی مذہب کے دوفریق میں کوئی خاص تعلیم کے متعلق اختلاف ہو، ایک فریق
ایک تعلیم کو اس مذہب کی جزو قرار دیتا ہو اور دوسرا فریق اس بات پر زور دیتا ہو کہ یہ اس
مذہب کی تعلیم نہیں ہے تو ایسی صورت میں ایک فریق دوسرے فریق کو یہ جواب دے کر
خاموش نہیں کر سکتا کہ یہ مذہبی امر ہے اس میں عقل کو کوئی دخل نہیں.کیونکہ دوسرا فریق اس
کو مذہبی امر
تسلیم نہیں کرتا.ایسے اختلاف کی صورت میں ضروری ہوگا کہ ہر ایک فریق اپنے
دعویٰ کی تائید میں دلائل پیش کرے.وہ دلائل عقلی بھی ہو سکتے ہیں اور نعلی بھی اور پھر نقلی
دلائل کی تفسیر میں عقل کا دخل ہوگا.ایک فریق ایک آیت یا ایک روایت کے ایک معنی کرتا
ہے اور دوسرا فریق اسی آیت یا روایت کے اور معنے کرتا ہے.ایسے موقع پر عقل ہی فیصلہ
کرے گی کہ کس کے معنے درست اور صحیح ہیں.ناظرین ہر دو فریق کے دلائل پر غور کریں
Page 140
137
گے اور اپنی عقل خدا داد کے ذریعہ ایک فریق کے حق پر ہونے اور دوسرے فریق کے باطل
پر ہونے کے بارے میں اپنی رائے قائم کریں گے اور جہاں آیات و روایات کے معانی
میں اختلاف ہو گا وہاں بھی اس بحث کو سننے اور پڑھنے والے غور وفکر کے بعد خود فیصلہ کریں
گے کہ کس کے معنے درست ہیں اور کس کے غلط؟
نیز یہ بھی یاد رکھنا چاہئیے کہ ایک چیز کا سمجھ میں نہ آنا اور بات ہے اور اس کا خلاف
عقل ہونا اور چیز ہے.مسیحی لوگ تثلیث فی التوحید اور کفارہ کو پیش کرتے ہیں.کیا وہ ان
عقائد کی تائید میں مولوی شاکر حسین صاحب کے الفاظ میں معترضین کو یہ جواب دے سکتے
ہیں کہ یہ لازمی نہیں ہے کہ جملہ مسائل دینی پر ہمارا فلسفی اور منطقی استدلال منطبق ہو سکے یا
ہم ان کی علت دریافت کرنے کا حق رکھتے ہوں اور یہ کہ یہ مسائل اسرار میں سے ہیں
انسانی عقل ان کی گنہ تک نہیں پہنچ سکتی.ہم مسیحیوں کو ان کی اس دلیل کے جواب میں یہ
کہیں گے کہ یہ باتیں عقل سے بالا نہیں بلکہ عقل اور فطرت کے خلاف ہیں اس لئے ہم ان
کو قبول کرنے کیلئے تیار نہیں.اسی طرح ہم حامیان قتل مرتد کے جواب میں یہی کہیں گے
کر قتل مرتد کا مسئلہ عقل سے بالا نہیں بلکہ یہ عقل کے خلاف ہے اس لئے ہم اس کو قبول
کرنے کیلئے آمادہ نہیں.اگر اس طریق استدلال کی پیروی کی جاوے تو ہر ایک انسان
ایک لغو سے لغو عقیدہ کو اپنے مذہب کی طرف منسوب کر کے یہ حجت پیش کر سکتا ہے کہ یہ
دین کے اسرار میں سے ہے اس لئے اس پر جرح کرنے کا کسی کو حق نہیں.غرض عقل کے متعلق مولوی شاکر حسین صاحب سہسوانی اور ان کے ہم خیال علماء
نے جو کچھ لکھا ہے اس سے یہ امر روز روشن کی طرح ہویدا ہوتا ہے کہ یہ صاحب عقلی معیار
کے زور سے اس مسئلہ کو صحیح ثابت کرنے کے لئے بالکل تیار نہیں.ہاں مولوی شبیر احمد
صاحب کا دعوی ہے کہ قتل مرتد عقل سلیم کے رو سے ضروری ہے اور اس کے لئے وہ اپنی
کتاب میں ایک خاص عنوان قائم کرتے ہیں جس کے الفاظ یہ ہیں :.
Page 141
138
قتل مرتد کے متعلق قیاس شرعی اور عقلِ سلیم کا کیا حکم ہے؟“
مگر اس عنوان کے ماتحت وہ اپنے دعویٰ کی تائید میں ایک بھی عقلی دلیل پیش نہیں کرتے.صرف ایک دوسرے شخص کا قول نقل کرنے پر اکتفا کرتے ہیں لیکن جو شہادت انہوں نے
اپنے دعویٰ کی تائید میں پیش کی ہے اس سے اگر کچھ ثابت ہوتا ہے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ
مولوی صاحب خیر سے خود ہی عقلِ سلیم سے عاری ہیں کیونکہ جو قول انہوں نے نقل کیا ہے
وہ ان کے لئے بجائے مفید ہونے کے مضر ہے کیونکہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ محض ارتداد
کی سزا قتل نہیں.حالانکہ مولوی صاحب کا دعویٰ ہے کہ صرف ارتداد اور تنہا ارتداد ہی وہ
جرم ہے جس کے لئے اسلام میں قتل کی سزا مقرر کی گئی ہے.مولوی صاحب اپنے اس
دعویٰ کی تائید میں کہ مرتد کا قتل عقلِ سلیم کا اقتضاء ہے حافظ ابن القیم کا مندرجہ ذیل قول
نقل کرتے ہیں:.فاما القتل فجعله عقوبة اعظم الجنايات كالجناية على الانفس
فكانت عقوبة من جنسه وكالجناية على الدين بالطعن فيه والارتداد
عنه و هذه الجناية اولى بالقتل وكف عدوان الجاني عليه من كل
عقوبة اذ بقاؤه بين اظهر عباده مفسدة لهم ولا خير يرجى في بقائه
ولا مصلحة فاذا حبس شره و امسك لسانه وكف اذاه والتزم
الذل والصغار وجريان احكام الله و رسوله عليه واداء الجزية لم
يكن في بقائه بين اظهر المسلمين ضرر عليهم والدنيا بلاغ ومتاع
،،
الى حين.( اعلام الموقعین جلد ۲ صفحه (۲۱۸)
دو لیکن قتل کو سب سے بڑی ظلموں کی سزا قرار دیا ہے جیسا کہ کسی کی جان لے لینا.پس یہ سزا اس جرم کی جنس میں سے ہے اور جیسا کہ دین کے متعلق ظلم کرنا یعنی اس پر
طعن کرنا اور اس سے ارتداد اختیار کرنا اور اس ظلم کی سزا میں قتل کرنا اور اسی طرح ظالم
Page 142
139
کے دست تعدی کو روکنا تمام سزاؤں کی نسبت زیادہ مناسب اور موزوں ہے کیونکہ
ایسے ظالم کا لوگوں کے درمیان باقی رہنا ان کے بگاڑ کا موجب ہے اور اس کے باقی
رہنے میں کسی غیر اور نفع کی کوئی امید نہیں ہوسکتی.پس اگر وہ اپنے شر کو روک لے اور اپنی
زبان کو بند کر لے اور تکلیف دہی سے باز آجائے اور ذلت اور رسوائی اور اللہ تعالیٰ اور اس
کے رسول کے احکام کا اپنے اوپر جاری کرنا اور جزیہ کا ادا کرنا اختیار کر لے تو مسلمانوں
کے لئے اس کا ان کے درمیان باقی رہنا کسی قسم کے نقصان کا موجب نہیں ہوگا.پس وہ
دنیا میں اپنی زندگی تک فائدہ اٹھا سکتا ہے اور اپنے مقاصد کو حاصل کر سکتا ہے.“
مندرجہ بالا عبارت میں کھلے طور پر یہ امر بیان کیا گیا ہے کہ صرف ارتداد اور تنہا
ارتداد کی سزا قتل نہیں.اگر ایک شخص اسلام سے ارتداد اختیار کرتا ہے اور کسی شر کا ارتکاب
نہیں کرتا اور اپنی زبان کو اسلام پر طعنہ زنی کرنے سے روکے رکھتا ہے تو ایسا شخص قتل نہیں
کیا جائے گا بلکہ وہ ایک ذمی کی حیثیت میں اسلامی سلطنت کے ماتحت امن و امان سے
زندگی بسر کر سکتا ہے اور اس کو وہی حقوق حاصل ہوں گے جو دوسرے ذمیوں کو حاصل
ہیں یعنی اسلامی سلطنت اس کے مال اور جان اور عزت کی اسی طرح حفاظت کرے گی
جس طرح کہ دوسری رعایا کی حفاظت کرتی ہے.محض مرتد قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ وہی مرند
قتل کیا جائے گا جو طعن فی الدین کرتا ہے اور اپنے شر سے مسلمانوں کو ایذا دیتا ہے.مرتد
اپنے ارتداد کی وجہ سے قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ اپنے شر اور طعن فی الدین اور ایذاء المومنین
کی پاداش میں موت کی سزا پائے گا.پس معلوم ہوا کہ نفس ارتداد مستوجب قتل نہیں.مرتد ہو کر ایک انسان اسلامی
سلطنت کے ماتحت امن و امان سے اپنی زندگی بسر کر سکتا ہے.سزا صرف اس صورت میں
دی جائے گی کہ وہ مرتد ہونے کے بعد طعن فی الدین کرے اور اپنے شر سے مسلمانوں کو
اذیت پہنچائے.اب مولوی شبیر احمد صاحب خود ہی اپنے گریبان میں منہ ڈال کر بتائیں
Page 143
140
کہ حافظ ابن القیم کا قول ان کے دعوی کی تائید کرتا ہے یا تردید؟
مجھے مولوی صاحب کی عقل پر رہ رہ کر تعجب آتا ہے کہ انہوں نے حافظ ابن القیم کی
شہادت کو کیوں پیش کیا ؟ معلوم ہوتا ہے کہ باطل کی پیروی سے انسان کی عقل بالکل ساب
ہو جاتی ہے.آنکھوں پر پردہ پڑ جاتا ہے اور کان بو جھل ہو جاتے ہیں اور کچھ سمجھ نہیں آتا اور
بڑے بڑے علم وفضل کا دعویٰ کرنے والے حق پرستوں کے مقابل میں بچوں سے بھی زیادہ
نادان ہو جاتے ہیں اور ایسی بیوقوفی کی حرکات کرتے ہیں کہ دیکھنے والا حیران رہ جاتا ہے.ایسے ہی لوگوں کی نسبت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:.إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي أَذَانِهِمْ وَقُرًا (الكهف :58)
کہ ہم نے ان لوگوں کے دلوں پر یقینا کئی پردے ڈال دیئے ہیں تا کہ وہ نہ سمجھیں اور
ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دی ہے.مولوی شبیر احمد صاحب نے حافظ ابن القیم کے قول کی نقل کر کے صرف اپنی ہی
عقل کے پردوں کا ثبوت مہیا نہیں کیا.بلکہ مولوی ظفر علی خان صاحب کی ایک بڑ کو بھی
ساتھ ہی جھوٹا ثابت کیا ہے.مولوی ظفر علی خان صاحب نے لکھا تھا:.ابتدائے اسلام سے لے کر آج کے دن تک ایک شخص نے بھی اس بارے میں
یعنی محض ارتداد کو موجب قتل قرار دینے میں ) اختلاف نہیں کیا.لیکن مولوی شبیر احمد
صاحب کے پیش کردہ حوالہ نے اس دعوی کو غلط ٹھہرایا اور ثابت کر دیا کہ اسلام میں ایسے
لوگ گزرے ہیں جو اس بات کے قائل تھے کہ محض ارتداد کی سزا قتل نہیں ہے اور وہ لوگ
حافظ ابن القیم کے پایہ کے انسان تھے.آیت لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ پر ایک اور جرح
آیت لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ کے متعلق ایک اور جرح یہ کی گئی ہے کہ اس آیت
Page 144
141
کریمہ کا مفہوم بھی محل نظر ہے کیونکہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے ترجمہ میں اس
آیت کا ترجمہ یوں بیان فرماتے ہیں:.نیست جبر کردن برائی دین هر آئینه ظاهر شده است راه یابی از
گمراهی.66
اس کی تشریح وہ حاشیہ میں اس طرح فرماتے ہیں:.یعنی حجت اسلام ظاهر شد پس گویا جبر کردن نیست اگرچه
فی الجمله جبر باشد
حامیان
قتل مرتد لکھتے ہیں کہ
66
”اردو میں یہ مطلب اس طرح ادا کیا جا سکتا ہے کہ اسلام کے آتے ہی حق اور
باطل کا معیار دنیا کے سامنے آگیا اور انسان کے سامنے سچائی پیش کر دی گئی.اب اس کے
لئے بجز اس کے چارہ نہیں کہ اس سچائی کے سامنے سرتسلیم خم کر دے اور اگر نہ کرے تو اس کی
گردن عدوان و طغیان کے جھکانے کے لئے کچھ طریقے ایسے اختیار کرنے پڑیں گے جن
پر بظاہر جبر کا گمان ہو گا.لیکن وہ جبر دراصل جبر نہ ہو گا.“
حامیان قتل مرتد کی اصل غرض اس حوالہ کے پیش کرنے سے یہ ہے کہ وہ یہ
دکھا ئیں کہ اس آیت کریمہ کے معنوں میں اختلاف ہے اس لئے ہم اس سے اپنے حق میں
کوئی استدلال نہیں کر سکتے.کیونکہ جو معنے ہم نے اس آیت کریمہ کے کئے ہیں ان کے
بالکل الٹ معنے بھی اسی آیت سے نکالے گئے ہیں اور الٹ معنے کرنے والے حضرت
شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جیسی شان کے آدمی ہیں لیکن حامیان قتل مرتد کو معلوم ہونا چاہیے کہ
صرف اختلاف دکھانے سے ان کی نجات نہیں ہوسکتی.ان کا فرض ہے دوراہوں میں سے
ایک راہ اختیار کریں.یا تو وہ دلائل سے اس بات کا ثبوت دیں کہ اس آیت کے وہ معنے غلط
ہیں جن سے ہم نے عدم جواز اکراہ فی الدین کا استدلال کیا ہے.یا وہ اس بات کا اقرار
Page 145
142
کریں کہ یہ ایک مبہم آیت ہے جس سے دو متضاد مفہوم پیدا ہو سکتے ہیں اور چونکہ اس آیت
کریمہ سے اکراہ فی الدین کے جواز کا مفہوم نکالنے والے حضرت شاہ ولی اللہ جیسے بزرگ
انسان ہیں.اس لئے ہم جو از اکراہ کے مفہوم کو عدم جواز اکراہ کے مفہوم پر ترجیح دیں گے.لیکن حامیان قتل مرتد کی ضمیر خواہ کیسے ہی موٹے پردوں کے نیچے دبی ہوئی ہو بھی ان کو اس
بات کی اجازت نہیں دے گی کہ وہ یہ کہنے کی جرات کریں کہ یہ آیت مبہم ہے اور اس سے دو
متضاد مفہوم جو بالکل ایک دوسرے کی ضد ہیں پیدا ہو سکتے ہیں.کیونکہ یہ آیت ایسی صاف
اور کھلی ہے اور اس کا مفہوم ایسا واضح اور تین ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام
کے سہارے کے باوجود بھی حامیان
قتل مرتد اس بات کے کہنے کی جرات نہیں کر سکتے کہ وہ
اس آیت کو مبہم قرار دیں اور یہ کہیں کہ اس آیت سے دو متضاد مفہوم پیدا ہو سکتے ہیں.ایک
ہی آیت سے دو ایسے معنی نکالنا جو بالکل ایک دوسرے کی ضد ہوں.اور جن میں آپس میں
وہی نسبت ہو جو رات کو دن سے ہے بالکل ناممکن ہے.ایسا خیال کرنا کہ ایک ہی آیت سے
دو بالکل الٹ معنے نکل سکتے ہیں جن میں سے ایک دوسرے کی تردید کرتا ہے نعوذ باللہ خود
قرآن شریف پر اعتراض کرنا ہے.بے شک قرآن شریف کی آیات سے ایک سے زیادہ
فوائد پیدا ہو سکتے ہیں اور ایک ہی آیت مختلف معانی پر حاوی ہوسکتی ہے مگر وہ معانی ایک
دوسرے کی ضد نہیں ہو سکتے.وہ سب معانی ایسے ہوں گے جو ایک ہی وقت میں صحیح ہوں
گے اور ایک ان میں سے دوسرے معانی کا منافی نہیں ہوگا.مگر ایک آیت سے آپ ایسے دو
معنے نہیں نکال سکتے جو آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہوں.اگر ایک کو درست مانا جائے تو
دوسرا غلط ثابت ہو.پس حامیان قتل مرتد یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس آیت سے دو معنے نکل سکتے
ہیں.اکراہ فی الدین کے جواز کے معنے بھی اور عدم جواز کے معنے بھی.ایک ہی معنے درست
ہو سکتے ہیں یا تو جواز کے معنے درست ہیں یا عدم جواز کے.دونو درست نہیں ہو سکتے.پس آیت زیر بحث کو مبہم قرار دینے کا راستہ حامیان قتل مرتد پر بند ہے.اب ایک
Page 146
143
ہی راستہ ان کے لئے کھلا ہے کہ وہ ان معنوں کو غلط ثابت کر کے دکھا ئیں جن کے رُو سے
عدم جواز اکراہ کا استدلال کیا جاتا ہے.مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا بلکہ صرف حضرت
شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت نقل کرنے اور اردو میں اس عبارت کا مفہوم بیان کر
دینے پر اکتفا کیا ہے اور دو تین اور مؤیدین کا نام لکھ کر مولوی ظفر علی خان صاحب نے
جنہوں نے یہ قول پیش کیا ہے جھٹ آگے لکھا ہے لیکن میں اس تصریح کو نظر انداز کر کے
تھوڑی دیر کے لئے فریق ثانی ہی کے ترجمہ کو صحیح تسلیم کیے لیتا ہوں.“ جو لوگ مولوی
صاحب کے مضمون کو غور سے پڑھیں گے وہ ضرور اس امر کو نوٹ کریں گے کہ مولوی
صاحب نے اس مضمون میں یہ روش اختیار کی ہے کہ جو بات ان
کی تائید میں ہوتی ہے لیکن
دراصل اپنے قلب میں اس کو صحیح تسلیم نہیں کرتے.اس کو تو وہ نقل کرنے سے نہیں چوکتے
لیکن اتنی احتیاط کر لیتے ہیں کہ اس دلیل کو صرف دوسرے شخص کے منہ میں ڈال کر بیان کر
دیتے ہیں خود اس کی تائید کرنے سے خاموشی اختیار کرتے ہیں.ایسا ہی انہوں نے حضرت
شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر آیت لا اکراہ فی الدین کے متعلق رویہ اختیار کیا ہے
جس سے صاف ظاہر ہے کہ مولوی صاحب کو خود حضرت شاہ صاحب کی تفسیر سے اتفاق
نہیں بلکہ حق یہ ہے کہ مولوی صاحب اور ان کے دوسرے ہمنوا مولوی صاحبان نے
حضرت شاہ صاحب کی تفسیر کو درست نہیں سمجھا اور ان سب نے اصولی طور پر لا اکراہ فی
الدین کے وہی معنے درست تسلیم کئے ہیں جو بالصراحت ان الفاظ سے ظاہر ہوتے ہیں یعنی
یہ کہ دین میں کوئی جبر نہیں.ہاں اس بات کے ثابت کرنے کے لئے بے سو دکوشش کی ہے
کہ یہ حکم صرف خارج از اسلام لوگوں کے لئے ہے یعنی جو لوگ ابھی اسلام میں داخل نہیں
ہوئے ان کے متعلق حکم ہے کہ ان کو جبر کے ذریعہ اسلام میں داخل نہ کیا جاوے یعنی جو
لوگ ایک دفعہ اسلام قبول کر لیں اور پھر اس سے ارتداد اختیار کریں ان پر یہ آیت چسپاں
نہیں ہوتی.اس وقت میرے سامنے تین مضمون نگار ہیں.مولوی ظفر علی خان صاحب.
Page 147
144
مولوی شاکر حسین صاحب سہسوانی اور مولوی شبیر احمد صاحب دیو بندی.اور تینوں اس
بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ جبر کے ذریعہ کسی کو اسلام میں داخل کرنا جائز نہیں جس کے یہ معنے
ہیں کہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر لا اکراہ فی الدین درست نہیں
کیونکہ حضرت شاہ صاحب کی تفسیر کی جو تشریح مولوی ظفر علی خان صاحب نے کی ہے اس
کے یہی معنی ہیں کہ اسلام میں داخل کرنے کے لئے جبر سے کام لینا چاہئیے.پس جس تفسیر
کے ساتھ خود مولوی ظفر علی خان صاحب کو اتفاق نہیں اس کو مولوی صاحب اپنی تائید میں
کیوں پیش کرتے ہیں.کیا اسی کا نام انصاف اور دیانتداری ہے؟
حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی بلندشان اور عالی مرتبہ کا پورا پورا احترام کرتے
ہوئے میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ ان کی تفسیر صاف بتا رہی ہے کہ انہوں نے لا اکراہ
في الدین کی تفسیر کرنے میں ایک خاص عقیدہ کی اتباع میں تکلف سے کام لیا ہے.بعض
مسلمانوں میں غلط فہمی سے یہ عقیدہ پیدا ہو گیا کہ اسلام مشرکوں اور اہل الاوثان کو کوئی پناہ
نہیں دے سکتا.ان کے لئے دو ہی راہیں کھلی ہیں یا اسلام قبول کریں یا تلوار.ظاہر ہے کہ
یہ ایک جبر کی راہ ہے اور آیت لا اکراہ فی الدین کے صریح خلاف ہے.اس لئے جن
لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ مشرکین اور اہل اوثان کے لئے جبر جائز ہے انہوں نے آیت
لا اکراہ فی الدین کو اپنے اس عقیدہ کے خلاف پا کر اس کے متعلق تین مختلف راہیں
اختیار کی ہیں.ان میں سے بعض نے تو بڑی جد وجہد کے بعد اور اپنا بہت سا دماغ خرچ
کر کے اس آیت کے حقیقی معنوں کو جو بالکل واضح اور بین تھے نظر انداز کر کے اس کی
طرف ایسا مفہوم منسوب کیا جس کے متحمل اس آیت کے الفاظ ہرگز نہیں ہو سکتے تھے بلکہ یہ
مفہوم آیت کریمہ کے صحیح اور اصلی معنوں کے بالکل الٹ اور خلاف تھا.یعنی انہوں نے
اس آیت کریمہ کے یہ معنی کئے کہ دین میں زبر دستی اور جبر جائز ہے.دین کے لئے اگر کسی
پر جبر کیا جاوے تو وہ جبر نہیں کہلا سکتا.یہی معنی ہیں جن کو شاہ ولی اللہ علیہ الرحمۃ نے اختیار
Page 148
145
کیا.مگر دوسرے لوگوں نے ( جو اس گروہ کے ساتھ بالکل ہم خیال اور متفق الرائے تھے اور
جن کا عقیدہ بھی اس گروہ کی طرح یہی تھا کہ دین میں جبر کرنا جائز ہے) دیکھا کہ اس آیت
کے کھلے کھلے اور صریح الفاظ ایسے معنوں کی اجازت نہیں دیتے اور یہ کہ اس آیت کریمہ کی
طرف ایسے معنے منسوب کرنا سراسر تکلف اور بناوٹ ہے.اس لئے باوجود یکہ وہ اس گروہ
کے ساتھ بالکل ہم عقیدہ تھے اور جبر کو بالکل جائز قرار دیتے تھے ان کی طبیعتوں نے ان
معنوں کو قبول نہ کیا اور انہوں نے تسلیم کیا کہ اس سے انکار نہیں ہوسکتا کہ لا اکراہ فی
الدین کے بے شک یہی معنی ہیں کہ دین میں جبر نہیں ہونا چاہیئے لیکن انہوں نے اپنے
عقیدہ کے بچاؤ کی یہ راہ اختیار کی کہ کہہ دیا کہ یہ آیت منسوخ ہے.اس کے معنے بےشک
یہی ہیں کہ دین میں جبر نہیں ہونا چاہیئے.اس کے سوا کوئی اور معنی کرنا محض تکلف ہے مگر یہ
آیت منسوخ شدہ ہے اسلام میں اب اس پر عمل نہیں.ان کے بعد ایک تیسرا گروہ اٹھا.انہوں نے بھی دوسرے گروہ کے ساتھ اس امر
میں اتفاق کیا کہ بے شک یہ آیت کریمہ صاف اور واضح ہے اور اس کے یہی معنے درست
ہیں کہ دین میں جبر نہیں ہونا چاہئیے.لیکن یہ ایک اصولی آیت ہے.اصول حقیقتوں پر مبنی
ہوتے ہیں اور حقیقتیں دائمی سچائیاں ہیں جو کبھی منسوخ نہیں ہو سکتیں اس لئے یہ قول قابل
پذیرائی نہیں ہو سکتا کہ یہ آیت منسوخ ہے.لیکن چونکہ اس تیسرے گروہ کا بھی پہلے دو
گروہوں کی طرح یہی عقیدہ تھا کہ مشرکین اور اہل الا وخان کے لئے کوئی آزادی نہیں.ان کے لئے صرف دو ہی راہیں کھلی ہیں چاہیں تو اسلام قبول کر کے اپنی جان بچالیں چاہیں
تو مسلمانوں کی تلوار کا مزہ چکھ کر واصل جہنم ہوں.اس لئے انہوں نے اپنے اس عجیب و
غریب عقیدہ کی حفاظت کے لئے یہ تجویز نکالی کہ یہ آیت اپنے مفہوم میں عام نہیں ہے بلکہ
یہ صرف اہل کتاب کے لئے خاص ہے مشرکین اور اہل الاوثان اس سے مستثنیٰ ہیں.چنانچہ
فتح البیان جلد نمبر اصفحہ ۳۴۰ میں لکھا ہے:.
Page 149
146
" القول الثانى انها ليست بمنسوخة وانما نزلت في اهل الكتاب
خاصة و انهم لا يكرهون على الاسلام اذا ادّوا الجزية بل الذين
66
يكرهون هم اهل الأوثان فلا يقبل منهم الا الاسلام او السيف
پس یہی عقیدہ تھا کہ مشرکین اور اہل الاوثان سے سوائے اسلام یا تلوار کے اور کچھ
قبول نہ کیا جاوے اور ان کو اسلام لانے پر مجبور کیا جائے جو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ
کے لئے محرک ہوا کہ وہ لا اکراہ فی الدین کے ایسے معنی اختیار کریں جن سے جبر کی
اجازت ثابت ہو.اس لئے انہوں نے وہ معنے اختیار کئے جو میں اوپر نقل کر چکا ہوں.لیکن یہ صاف ظاہر ہے کہ وہ معنے تکلف سے بنائے گئے ہیں.اگر انسان خالی الذہن ہو کر
ان الفاظ کو پڑھے گا تو ان کے یہی معنے کرے گا کہ ان الفاظ میں جبر وا کراہ کی ممانعت کی گئی
ہے.کسی اہل زبان سے یا ایسے شخص سے جو عربی دان کہلا سکتا ہو لا اکراہ فی الدین کے
معنی پوچھو تو وہ اس کے یہی معنی کرے گا کہ ان الفاظ میں جبر واکراہ کی ممانعت پائی جاتی
ہے.یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں میں سے بھی جو مشرکین کے لئے جبر جائز قرار دیتے
ہیں اکثر نے لا اکراہ فی الدین کے یہی معنے لئے ہیں کہ دین میں اکراہ نہیں ہونا چاہیئے
اور اس وقت بھی جن مولوی صاحبان نے موجودہ بحث میں حصہ لیا ہے انہوں نے بھی
با وجود حضرت ولی اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو پیش کرنے کے خودان معنوں کو
اختیار نہیں کیا بلکہ عملی طور پر وہی معنے تسلیم کئے ہیں جو اس آیت کے صاف اور کھلے کھلے معنے
ہیں.اور اگر چہ بہت حیلہ بازی سے کام لے کر مرتد کو اس آیت کریمہ کے دائرہ سے باہر
رکھنے کی ناکام کوشش کی ہے لیکن اس سے انکار نہیں کر سکے کہ لا اکراہ فی الدین کے معنے
یہی ہیں کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہونا چاہئیے.حضرت شاہ ولی اللہ رحمتہ اللہ علیہ کا اپنے ایک عقیدہ کے ماتحت اس آیت کی تفسیر
میں اس کے متبادر اور حقیقی معنوں کو نظر انداز کر کے ایک ایسے مفہوم کو اختیار کرنا جو تکلف
Page 150
147
سے اس آیت کی طرف منسوب کیا گیا ہے کوئی تعجب کی بات نہیں.اور اس سے یہ نہیں سمجھنا
چاہئیے کہ اس آیت کے الفاظ کافی واضح نہیں تھے اور ان میں اس امر کی گنجائش تھی کہ کوئی
دوسرے معنے جو حقیقی معنوں سے بالکل متضاد تھے ان کی طرف منسوب کئے جاتے.اس
امر کے متعلق ہمیں ذرا بھی تعجب نہیں رہتا جب ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے مفسروں نے
ایک غلط عقیدہ سے متاثر ہوکر لفظ توفی کے ایسے معنے کئے جو کبھی بھی اس لفظ کی طرف
منسوب نہیں کئے گئے تھے.لغت بلا اختلاف کہتی ہے کہ تَوفَّی اللہ زَيْدًا کے معنے سوائے
قبض روح کے اور کوئی نہیں.قرآن شریف میں جہاں جہاں یہ لفظ استعمال ہوا ہے وہاں
سوائے قبض روح کے اور کوئی معنے نہیں.حدیث میں بھی یہی معنے ہیں.کلام عرب میں بھی
یہی معنے ہیں.لیکن باوجود اس عالمگیر اتفاق کے جب یہی لفظ ایک سے زیادہ دفعہ حضرت
عیسی علیہ السلام کے متعلق قرآن شریف میں استعمال ہوا تو اپنے اس غلط عقیدہ سے متأثر
ہو کر کہ حضرت عیسی علیہ الصلوۃ والسلام زندہ آسمان پر اٹھائے گئے لفظ توفی کے وہ معنی
کئے جو دنیا جہان میں کسی نے نہیں کئے تھے.خود قرآن شریف میں وہی لفظ بار بار آتا ہے
وہاں اس کے معنے قبض روح کے لیتے ہیں لیکن جب اسی کتاب میں وہی لفظ حضرت عیسی
علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت استعمال ہوتا ہے تو ان کا عقیدہ ان کو اجازت نہیں دیتا کہ اس
لفظ کے وہی معنے کریں جو ہر دوسرے مقام میں کئے جاتے ہیں اس لئے وہ ایک نئے معنے
اپنی طرف سے تراش کر اس لفظ کو دیتے ہیں.پس اس مثال کے ہوتے ہوئے اگر ایک
عقیدہ کے ماتحت آیت لا اکراہ فی الدین کی طرف کوئی نئے معنے منسوب کرنے کی
کوشش کی گئی تو اس سے ہر گز تعجب نہیں کرنا چاہیئے.ہاں اگر یہ بزرگ حضرت
مسیح موعود کا زمانہ پاتے اور اس ظلم و عدل کا کلام سنتے
جس کو اللہ تعالیٰ نے اس زمانہ میں ایسی غلطیوں سے اسلام کو پاک کرنے کے لئے مبعوث
فرمایا تو یقیناً وہ اول المومنین میں ہوتے اور ان کو اپنی غلط فہمیوں سے دست بردار ہونے
Page 151
148
میں ذرہ بھی تامل نہ ہوتا.اس جگہ میں مولوی ظفر علی خان صاحب کی خدمت میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں
کہ کسی بزرگ کی نسبت جو مامور نہ ہو یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ ہر ایک امر دینی میں غلطیوں سے
پاک تھے اور یہ ناممکن ہے کہ ان سے کوئی غلطی خواہ اجتہادی ہی کیوں نہ ہو سرزد ہو اور اس
لئے جو کچھ انہوں نے فرمایا وہ راست اور درست ہے اِتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ
آربابا (التوبة : 31) کا اپنے آپ کو مصداق بنانا ہے.اگر چہ آیت زیر بحث ایسی صاف اور تین ہے کہ اس کی وضاحت کے لئے تفاسیر
کے اقوال کو پیش کرنے کی کچھ بھی ضرورت نہیں اور یہ آیت کریمہ اس حاجت سے مستغنی
ہے کہ اس کے مفہوم کو واضح کرنے کے لئے علماء اسلام کی تفاسیر پیش کی جائیں.لیکن مزید
اتمام حجت کے لئے میں مناسب دیکھتا ہوں کہ اس آیت کریمہ کے متعلق بعض تفاسیر سے
بھی کچھ اقتباس نقل کروں تا حامیان قتل مرتد کو موازنہ کرنے کا موقع ملے اور وہ اپنی عقل
خداداد سے کام لے کر یہ فیصلہ کرسکیں کہ لا اکراہ فی الدین کے یقینی اور قطعی معنے کیا ہیں.پہلے میں اس آیت کے شان نزول کے متعلق جو روایات ہیں وہ نقل کرتا ہوں.شان نزول سے بھی حامیان قتل مرتد کو اس آیت کے صحیح مفہوم کے متعلق رائے قائم کرنے
میں مدد ملے گی.(۱) لباب النقول فى اسباب النزول بر حاشیه جلالین مطبوعه مصر
جلد اول صفحہ ۵۰ میں لکھا ہے:.دو
روی ابوداؤد و نسائی و ابن حبان عن ابن عباس قال كانت المرءة
مقلاة فتجعل على نفسها ان عاش لها ولد ان تهوده فلما اجليت
بنو النضير كان فيهم من ابناء الانصار فقالوا لاندع ابناء نا فانزل
الله لا اکراه فی الدین“
Page 152
149
مدینہ کی عورتوں میں یہ رسم تھی کہ جس عورت کی اولاد کم ہوتی تھی تو وہ یہ نذر مانتی تھی
کہ اگر اس کا بیٹا زندہ رہا تو وہ اس کو یہودی بنادے گی.اور جب بنو نضیر کے متعلق جلا وطنی کا
حکم ہوا تو ان میں انصار کے بیٹے بھی تھے.انصار نے کہا کہ ہم اپنے بیٹوں
کو نہیں چھوڑیں
گے.تب یہ آیت اتری کہ لا اکراہ فی الدین.(۲) اخرج سعيد بن منصور وعبدالله ابن حمید و ابن جریر و ابن
المنذر والبيهقي عن سعيد ابن جبير في قوله لا اکراه فی الدین.قال
نزلت في الانصار خاصة قلت خاصة قال خاصة كانت المرءة
منهم اذا كانت نزورة او مقلات تنذر لين ولدت ولدا لنجعلنه في
اليهود تلتمس بذلك طول بقاءه فجاء الاسلام وفيهم منهم.فلما
اجليت النضير قالت الانصار يا رسول الله ابناء نا واخواننا فيهم
فسكت عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت لا اكراه في
الدين“ (در منثور جلد ا صفحه ۳۲۹)
سعید نے کہا کہ آیت لا اکراہ فی الدین خصوصیت کے ساتھ انصار کے بارہ
میں نازل ہوئی.میں نے پوچھا.کیا خصوصیت کے ساتھ انصار کے بارہ میں یہ آیت نازل
ہوئی ؟ اس نے جواب دیا کہ ہاں خصوصیت کے ساتھ انہی کے بارہ میں یہ آیت اتری.جب کسی انصار کی عورت کی اولاد کم ہوتی تو وہ نذر مانتی تھی کہ اگر اس کے ہاں بیٹا ہوتو وہ اس
کو یہود میں داخل کر دے گی اور اس سے اس کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ یہ بیٹا زندہ رہے.جب اسلام آیا اس وقت یہود میں انصار کی اولا د موجود تھی.جب بنو نضیر کو جلا وطنی کا حکم ملا تو
انصار نے کہا کہ اے خدا کے رسول ہمارے بیٹے اور ہمارے بھائی یہود میں موجود ہیں.آپ خاموش ہو گئے.تب یہ آیت نازل ہوئی.لَا إِكْرَاهَ فِی الدِّينِ.(۳) عن مجاهد قال كان ناس من الانصار مسترضعين في بني
Page 153
150
قريظة فثبتوا على دينهم فلما جاء الاسلام اراد هلوهم ان يكرهو هم
على الاسلام فنزلت لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ
(در منثور جلد اصفحه ۳۲۹)
انصار کے بعض آدمیوں نے بنوفر یضہ میں پرورش پائی تھی اور وہ انہی کے دین پر
قائم ہو گئے تھے.جب اسلام آیا تو ان کے رشتہ داروں نے چاہا کہ ان کو اسلام لانے پر
مجبور کریں.تب یہ آیت اتری لا اکراه فی الدین.(۴) عن ابن عباس في قوله لا اكراه فى الدين قال نزلت في رجل
من الانصار من بنى سالم بن عوف يقال له الحصين.كان له ابنان
نصرانيان وكان هو رجلا مسلمًا.فقال للنبي صلى الله عليه وسلم
الا استكرهُهُما فانّهما قد ابيا الا النصرانية فانزل الله فيه ذلك
(در منثور جلد اصفحه ۳۲۹)
حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ آیت کریمہ لا اکراہ فی الدین ایک انصاری
کے بارہ میں اتری جو بنو سالم بن عوف کے قبیلہ میں سے تھا اور جس کا نام حصین تھا.اس
کے دو بیٹے نصرانی تھے اور وہ خود مسلمان تھا.اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت
میں عرض کیا کہ کیا میں ان کو جبر سے مسلمان نہ بنالوں؟ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نصرانی رہیں
گے.تب اس امر کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری.ان تمام روایتوں کا اس امر پر اتفاق ہے کہ یہ آیت انصار کی اولاد کے بارہ میں
اتری.جو نصرانی یا یہودی ہو گئے تھے اور ان کے مسلمان رشتہ دار چاہتے تھے کہ جبر سے ان
کو مسلمان بنالیں اس کی ممانعت میں یہ آیت اتری.اب میں حامیان قتل مرتد سے پوچھتا
ہوں کہ اس شان نزول کے مطابق آیت لا اکراہ فی الدین کے کیا معنے ہونے چاہئیں.کیا یہ کہ بے شک جبر سے لوگوں کو مسلمان بنالو.جبر سے اسلام میں لوگوں کو داخل کرنا جبر
Page 154
151
نہیں کہلا تا یا یہ کہ جبر سے کسی کو اسلام میں داخل نہیں کرنا چاہیئے.اب میں اس آیت کریمہ کے متعلق دو اور روایتیں نقل کرتا ہوں جن سے معلوم ہوتا
ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس آیت کریمہ کے یہ معنے نہیں سمجھتے تھے کہ دین کے لئے جبر
کرنا جائز ہے بلکہ ان کے نزدیک بھی اس آیت کریمہ کے یہی معنے تھے کہ جبر سے کسی شخص
کو دین میں داخل نہیں کرنا چاہئیے.(۱) اخرج سعيد ابن منصور و ابن ابی شیبه و ابن المنذر وابن ابى
حاتم عن وسق الرومى قال كنت مملوكًا لعمر بن الخطاب فكان
يقول لي اسلم فانك لو اسلمت استعنت بك على امانة
المسلمين فانى لا استعين على امانتهم بمن ليس منهم فابيت عليه
فقال لى لا اكراه في الدین (در منثور جلد ا صفحه ۲۳۰)
وسق رومی کہتا ہے کہ میں حضرت عمر بن الخطاب کے پاس غلام تھا.آپ مجھے فرمایا
کرتے تھے کہ تو مسلمان ہو جاتا کہ مسلمانوں کے معاملات میں جو میرے سپرد ہیں تجھ سے
مدد لے سکوں.میں ایسے امور میں ایسے شخص سے مدد لینا نہیں چاہتا جو مسلمان نہ ہو.میں
نے مسلمان ہونے سے انکار کیا.آپ نے فرمایا لا اکراہ فی الدین.(۲) اخرج النحاس عن اسلم سمعت عمر بن الخطاب يقول
لعجوز نصرانية اسلمى تسلمى.فابت.فقال عمر اللهم اشهد.ثم
تلالَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ.“
اسلم کہتا ہے کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سناوہ ایک نصرانی بڑھیا کو کہہ رہے
تھے کہ مسلمان ہو جاؤ.خدا تعالیٰ تمہیں بچالے گا.اس نے انکار کیا.حضرت عمرؓ نے فرمایا
اے اللہ گواہ رہ.پھر آپ نے یہ آیت پڑھی لا اکراہ فی الدین.اب میں بعض مفسروں کا قول نقل کرتا ہوں اس سے بھی امید ہے کہ انشاء اللہ تعالیٰ
Page 155
152
حامیان قتل مرتد کو نفع پہنچے گا.ابن کثیر اپنی تفسیر میں کہتا ہے.اى لا تكرهوا احدًا على الدخول في دين الاسلام فانه بين واضح
جلی دلائله و براهينه لا يحتاج الى ان يكره احد على الدخول فيه
بل من هداه الله الى الاسلام وشرح صدره ونور بصيرته دخل فيه
على بينة ومن اعمى الله قلبه وختم على سمعه وبصره فانّه لا يفيده
الدخول في الدين مكرها مقسورا وقد ذكروا ان سبب نزول هذه
الآية في قوم من الانصار وان كان حكمها عامًا
(ابن کثیر برحاشیہ فتح البیان صفحه ۱۵۱)
لا اکراہ فی الدین کے یہ معنے ہیں کہ کسی کو دین اسلام میں داخل ہونے کے لئے
مجبور نہ کرو کیونکہ وہ کھلا کھلا اور واضح ہے اور اس کے دلائل اور براہین روشن ہیں اور وہ اس
بات کا محتاج نہیں کہ کسی کو اس میں داخل ہونے کے لئے مجبور کیا جاوے بلکہ جس شخص کو
اللہ تعالیٰ اسلام کی طرف راہنمائی فرماتا ہے اور اس کے سینے کو کھول دیتا ہے اور اس کو نور
بصیرت عطا فرماتا ہے تو ایسا شخص علی بصیرت اسلام میں داخل ہو جاتا ہے اور جس کے دل کو
اللہ تعالیٰ اندھا کر دیتا ہے اور اس کے کان اور آنکھ پر مہر کر دیتا ہے تو ایسے شخص کو اگر جبر سے
اسلام میں داخل کیا جاوے تو اس سے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا اور بیان کیا گیا ہے کہ یہ
آیت انصار کی ایک قوم کے بارے میں نازل ہوئی اگر چہ اس
کا حکم عام ہے.حامیان
قتل مرتد ابن کثیر کی تفسیر کوغور سے پڑھیں اور سچ بتائیں کہ یہ تفسیر ان کے
دل کو بھاتی ہے یا نہیں ؟ اور خود ہی انصاف سے فرمائیں کہ لا اکراہ فی الدین کی کون سی
تفسیر ان کو زیادہ معقول معلوم ہوتی ہے؟ آیا یہ تفسیر کہ جتنا چاہو جبر کر لو اور لوگوں کو جبر سے
اسلام میں داخل کر لیا کرو.جبر سے اسلام منوانا جب نہیں کہلاسکتا یا ی تعلیم کہ اسلام اس بات کا
محتاج نہیں کہ لوگوں کو جبر سے اس میں داخل کیا جاوے اور جبر سے کسی کو اسلام میں داخل
Page 156
153
کرنا ایک بیہودہ حرکت ہے کیونکہ ایسے اسلام لانے کا اس کو کچھ بھی فائدہ نہیں؟ نیز میں
حامیان قتل مرتد سے یہ بھی پوچھتا ہوں کہ جو شخص اسلام قبول کرنے کے بعد پھر ارتداد
اختیار کرنا چاہے ایسے آدمی کو اگر جبر سے اسلام میں رکھا جائے گا تو اس سے اس شخص کو کیا
فائدہ ہوگا؟ ابن کثیر تو فرماتے ہیں کہ ایسے اسلام سے اس شخص کو کچھ فائدہ نہیں پہنچے گا.مولوی صاحب! آپ صاحبان کی اس کے متعلق کیا رائے ہے؟ اب حامیان قتل مرتد
دیکھیں کہ بحر المحیط میں کیا لکھا ہے:.وقيل لايـكـره على الاسلام من خرج الى غيره وقال ابو مسلم
والـقــفــال معناه انه مابنی تعالی امرالایمان على الاجبار والمقسر
وانما بناه على التمكن والاختيار ويدل على هذا المعنى انه لما بين
دلائل التوحيد بيانا شافيا.قال بعد ذلك لم يبق عذر في الكفر الا
ان يقسر على الايمان ويجبر عليه وهذا مالا يجوز في دار الدنيا التي
هي دار الابتلاء اذ فى القهر والاكراه على الدين بطلان معنى الابتلاء
يؤكد هذا قوله "وَقَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ“ یعنی ظهرت الدلائل
ووضحت البينات ولم يبق بعدها الا طريق القسر واالالجاء وليس
بجائز لانه ينا فى التكليف (بحر المحيط جلد ۲ صفحه ۲۸۲٬۲۸۱)
بعض نے لا اکراہ فی الدین کے یہ معنی بھی کئے ہیں کہ جو شخص اسلام سے
نکل کر کوئی اور دین اختیار کرے ( یعنی ارتداد اختیار کرے) تو ایسے شخص کو اسلام پر مجبور نہ
کیا جاوے اور ابو مسلم اور قفال کا یہ قول ہے کہ اس آیت کریمہ کے یہ معنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ
نے ایمان کا معاملہ جبر و اکراہ پر مبنی نہیں کیا بلکہ اس کی بنیا د انسان کے اختیار اور قدرت پر
رکھی ہے.جب اللہ تعالیٰ نے توحید کے دلائل کو خوب کھول کر بیان فرما دیا تو اب کسی کے
پاس کفر پر رہنے کے لئے کوئی عذر باقی نہیں.اب بھی اگر وہ اسلام کو قبول نہیں کرتا تو اس کا
Page 157
154
ایک ہی علاج ہو سکتا تھا کہ اس کو اسلام لانے پر مجبور کیا جاوے.لیکن اس دنیا میں ایسا کرنا
جائز نہیں کیونکہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے اور زبردستی کرنے اور جبر سے اسلام منوانے
میں آزمائش کا اصول باطل ہو جاتا ہے.اور لا اکراہ فی الدین کے ان معنوں کی
اللہ تعالیٰ کا یہ قول تائید کرتا ہے.قد تبين الرشد من الغتی یعنی دلائل ظاہر ہو گئے اور
بینات واضح ہو گئیں.اب ایک جبر کا ہی طریق باقی تھا اور یہ جائز نہیں کیونکہ یہ انسان کے
مکلف ہونے کے اصول کے منافی ہے.“
مندرجہ بالا حوالہ سے ایک بات نئی معلوم ہوئی اور وہ یہ کہ بعض لوگوں نے لا اکراہ
فی الدین کے یہ معنی بھی کئے ہیں کہ اگر کوئی شخص اسلام سے ارتداد اختیار کرے تو ایسے
آدمی پر جبر نہیں کرنا چاہئیے.اس سے معلوم ہوا کہ بعض ایسے لوگ گزرے ہیں جو آیت
لا اکراہ فی الدین کے ماتحت یہ جائز نہیں سمجھتے تھے کہ کسی کو اسلام پر رکھنے کے لئے جبر کا
استعمال کیا جائے اور مرتدین کو مجبور کیا جاوے کہ وہ دوبارہ اسلام میں داخل ہوں اووہ ان
لوگوں کے ساتھ متفق نہیں تھے جو قتل مرتد کی حمایت میں یہ کہتے ہیں کہ لا اکراہ فی الدین
ان لوگوں کے لئے ہے جو ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے اور جولوگ اسلام میں داخل ہو
جاویں ان کے لئے جبر جائز ہے.ایسے لوگوں کو جبر سے اسلام میں رکھا جاسکتا ہے اور اسی
لئے شارح نے قتل مرتد کا حکم دے رکھا ہے.پس حامیان قتل مرتد کا وہ دعویٰ غلط ثابت ہوا کہ ابتدائے اسلام سے لے کر آج
تک ایک فرد نے بھی اس مسئلہ کے متعلق اختلاف نہیں کیا.حافظ ابن القیم کا قول تو خود
مولوی شبیر احمد صاحب نے نہایت ہی مہربانی فرما کر مہیا فرمایا ہے اور یہ دوسرا قول
بحر المحیط والے نے پیش کیا ہے.اب میں فتح البیان جلد اول صفحہ ۳۴۰ سے ایک عبارت
نقل کر کے لا اکراہ فی الدین کی بحث کو ختم کرتا ہوں.صاحب فتح البیان فرماتے ہیں:.وقال في الكشاف في تفسير هذه الآية اى لم يجر الله امر الايمان
Page 158
155
على الاجبار والقسر ولكن على التمكنّ والاختيار و نحوه قوله
وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ
النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ - اى لو شاء لقسرهم على الايمان
ولكن لم يفعل وبنى الامر على الاختيار.“
اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کشاف میں لکھا ہے کہ اس آیت کریمہ کے یہ معنے
ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کے امر کو جبر و اکراہ پر جاری نہیں کیا بلکہ قدرت اور اختیار پر چھوڑ
رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ کا یہ قول بھی اسی بات کی تائید کرتا ہے:.وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَا مَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ
النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (يونس: 100)
یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان لوگوں کو ایمان لانے پر مجبور کرتا لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا
نہیں کیا اور اس بات کو انسان کے اختیار پر چھوڑ دیا ہے.چکی ہے.اب میں خیال کرتا ہوں کہ لا اکراہ فی الدین کے مفہوم کے متعلق کافی بحث ہو
کافی ہے
سمجھنے کو اگر اہل کوئی ہے.
Page 159
156
حدیث اور قتل مرند
جب قرآن شریف کی آیات بینہ سے روز روشن کی طرح یہ ثابت ہو چکا کہ کسی شخص کو
محض ارتداد کے لئے قتل کرنا اسلام کی تعلیم کی صریح خلاف ورزی ہے تو اس کے بعد ضرورت
نہ تھی کہ کسی اور چیز کی طرف رجوع کیا جاتا لیکن چونکہ مخالفین کو اس بات پر گھمنڈ ہے کہ
حدیث سے ثابت ہے کہ ارتداد اور محض ارتداد کی سزا قتل ہے.اس لئے ضروری معلوم ہوتا
ہے کہ حدیث پر بھی نظر کی جائے اور دیکھا جائے کہ یہ دعوی کہاں تک درست ہے؟
قرآن شریف کے مقابل میں حدیث کا درجہ
حامیان
قتل مرتد کا ضمیر نہایت سختی کے ساتھ اس امر کو محسوس کر چکا ہے کہ قرآن
شریف قتل مرتد کے عقیدہ کو دھکے دے رہا ہے اور یہ کہ قرآن شریف کی تعلیم کے سامنے
قتل مرتد کا خیال ایک آن کے لئے بھی ٹھہر نہیں سکتا.اس لئے جب ان سے مطالبہ کیا گیا
کہ جن روایات کوتم قتل مرتد کی تائید میں پیش کرتے ہو آؤ قرآن شریف کی آیات کی روشنی
میں ان کو رکھو.تا معلوم ہو کہ ان روایات سے جو استدلال تم نے کیا ہے وہ کہاں تک
درست اور صحیح ہے تو حامیان قتل مرتد کے اعضاء پر رعشہ طاری ہو گیا اور وہ اس مطالبہ کوسن
کر بہت گھبرائے ہیں اور یہ امران کو موت سے سخت تر معلوم ہوا ہے کہ ان روایات کی صحت
یا ان کے حقیقی معنوں کو قرآن شریف کی مدد سے دریافت کریں.قرآن شریف سے اپنے
آپ
کو بچانے کے لئے حامیان قتل مرتد نے جو عذرات پیش کئے ہیں وہ یہ ہیں.حاشیہ لے اس مضمون کے متعلق مفصل معلومات حاصل کرنے کے لیے ناظرین الحق مباحثہ لدھیانہ
مطالعہ فرماویں.اس مضمون میں بھی حضرت مسیح موعود کی کتب ازالہ اوہام اور مباحثہ لدھیانہ سے اقتباس
لئے گئے ہیں.منہ
Page 160
157
(۱) احادیث کو قرآن شریف کے ذریعہ جانچنے کا قاعدہ دُنیا جہان سے نرالا کلیہ
ہے.“ جو وضع کیا گیا ہے.(۲) امام بخاری جیسے بزرگ کی نسبت یہ خیال بھی دل میں لانا ایک حیرت انگیز
جرات ہے کہ امام موصوف اپنے مجموعہ میں کوئی ایسی حدیث درج کر سکتے ہیں جو
قرآن شریف کے مخالف ہو.(۳) یہ خیال کہ جو حدیث صحت و درستی کے مقررہ اور مفید یقین معیار پر پوری
اترے اس کا معارض نصِ قرآنی ہونا، اس کی پذیرائی کے مانع ہے.اہل علم کے نزدیک
پر کاہ جتنی وقعت بھی نہیں رکھتا.(۴) ایک شخص ایک حدیث کو صحیح مان رہا ہے اور وہ اس کے نزدیک کسی قرآنی نص
کے معارض نہیں لیکن دوسرے کا فہم و تدبر اس پر تعارض کا حکم لگا رہا ہے پھر اس اختلاف کے
ہوتے ہوئے دواوین پر حدیث کی کوئی حیثیت باقی رہ سکتی ہے؟ اگر ہر زید و بکر کے فہم ہی کو
فیصلہ کا معیار مان لیا جائے تو احادیث تو در کنار خود آیات میں بھی ظاہر بینوں کو تعارض کی کئی
مثالیں مل سکتی ہیں.(۵) جو حدیث محدثین کے اصول کے رو سے صحیح ثابت ہو جائے اس کا معارض
قرآن ہونا قطعاً غیر ممکن ہے.ان سب عذرات کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ اس بات کیلئے ہرگز تیار نہیں کہ وہ اپنی
پیش کردہ روایات کو قرآن شریف کی آیات کے سامنے رکھیں.بلکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم
نہ صرف ان روایات کو صحیح اور درست تسلیم کر لیں جو حامیان
قتل مرتد نے اپنی تائید میں پیش
کی ہیں بلکہ ان معنوں کو بھی صحیح یقین کر لیں جو وہ لوگ ان کی طرف منسوب کرتے ہیں اور
قرآن شریف کا نام تک نہ لیں.تا ایسا نہ ہو کہ قرآن شریف کی آیات بینات ان روایات پر
ایسی روشنی ڈالیں جس کے ذریعہ ان کی حقیقت ظاہر ہو جائے اور حامیان قتل مرتد کا طلسم
Page 161
158
ٹوٹ جائے اور جو پر دہ وہ لوگوں کی آنکھوں پر ڈالنا چاہتے ہیں قرآن شریف اس پر دہ کو اٹھا
دے اور حقیقت کا انکشاف ہو جائے.لیکن معلوم ہونا چاہئیے کہ ان کے عذرات اس مشکل
سے ان کو نجات نہیں دے سکتے.وہ گھبرا کر کہتے ہیں کہ یہ دنیا جہان سے نرالا قاعدہ ہے جو وضع کیا گیا ہے.مگران کو
جانا چاہئے اول تو یہ قاعدہ نرالا نہیں لیکن محض نرالا ہونا کسی قاعدہ کو غلط ثابت نہیں کرتا.اس
قاعدہ کوغور سے دیکھو.اگر وہ قاعدہ معقول ہے تو اسے قبول کرنا چاہئے.اور اگر غیر معقول
ہے تو اسے رد کر دینا چاہئیے.صرف یہ کہہ کر کہ یہ ایک نیا معیار ہے جو پیش کیا گیا ہے آپ
کسی معیار کور دنہیں کر سکتے.اس معیار کو پرکھو.اس کا امتحان کرو.اگر امتحان کے بعد آپ
اس معیار کو مضبوط اور یقینی پاؤ تو اس کو اختیار کر ورنہ اس کو ترک کر دو.وہ معیار کیا ہے جو
اس بحث میں حدیث کے پر کھنے کے لئے پیش کیا گیا ہے.اس وقت آپ لوگوں نے
قتل مرتد کے دعوے کے ثبوت میں کچھ حدیثیں پیش کی ہیں.ہم نے اس دعوی کی تردید
میں قرآن شریف کو پیش کیا ہے اور ثابت کیا ہے کہ قتل مرتد کا مسئلہ قرآن شریف کی تعلیم
کے خلاف ہے اور تمہاری پیش کردہ حدیثوں کے متعلق یہ معیار پیش کیا ہے کہ ہم ان
حدیثوں کو قرآن شریف پر عرض کریں گے.اگر ان کو قرآن شریف کے مطابق پائیں گے
تو ان کو کمال خوشی سے قبول کریں گے اور اگر ان کے الفاظ میں اور قرآن شریف میں بظاہر
تعارض نظر آئے گا تو ہم قرآن شریف کو چھوڑ کر حدیثوں کے ان معنوں کو صحیح تسلیم نہیں کریں
گے جو قرآن شریف کی تعلیم کے صریح مخالف ہیں بلکہ ان احادیث پر غور کریں گے.اگر
ان احادیث کی کسی طرح قرآن شریف کی تعلیم سے تطبیق ہوسکی تو ہم ان معنوں کو صحیح تسلیم
کریں گے جو قرآن شریف کی تعلیم کے عین مطابق اور موافق ہیں اور ان معنوں کو ترک کر
دیں گے جو قرآن شریف کے مخالف ہیں لیکن اگر ان احادیث کی تطبیق قرآن شریف سے نہ
ہو سکی تو ہم مجبوراً ان احادیث کو قرآن شریف کے خلاف ہونے کی وجہ سے ترک کر دیں
Page 162
159
گے اور قرآن شریف کو ان احادیث پر مقدم رکھیں گے.یہ ہے وہ معیار جو ہم نے موجودہ
بحث میں امر زیر بحث کے تصفیہ کے لئے پیش کیا ہے.مگر حامیان
قتل مرتد اس معیار کو قبول
کرنے کے لئے تیار نہیں اور ان کا اس معیار کوقبول نہ کرنا اس امرکا قطعی اور یقینی ثبوت ہے
کہ وہ ان روایات کو قرآن شریف کی صریح تعلیم کے خلاف دیکھتے ہیں اور اگر وہ قرآن شریف
کا معیار قبول کر لیں تو انہیں ماننا پڑتا ہے کہ کسی مرتد کو محض ارتداد کے لئے قتل کرنا
جائز نہیں.اس لئے وہ اس معیار کو ہی قبول نہیں کر سکتے اور ہم سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ
ہم ان روایات کو انہی معنوں میں قبول کر لیں جو وہ ان روایات کی طرف منسوب کرتے
ہیں اور قرآن شریف کی روشنی میں ان روایات کو نہ جانچیں.میں فی الحال حامیان قتل مرتد پر یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اگر بفرض محال
اس معیار کونرالا بھی کہا جاوے پھر بھی یہ ایک ایسا معیار ہے کہ جس کو ہر ایک مومن بشرح
صدر قبول کرے گا.اور اگر کسی شخص کا سینہ نور ایمان سے خالی ہے تو وہ بھی معقولی رنگ میں
مجبور ہوگا کہ اس اصول کو صحیح تسلیم کرے.کیونکہ جو معیار ہماری طرف سے پیش کیا گیا ہے
اس کی معقولیت ایسے زبر دست دلائل سے ثابت ہے کہ کوئی ادنی تدبر سے کام لینے والا
انسان بھی خواہ وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو اس سے انکار نہیں کر سکتا اور مومن کی تو شان
ہی نہیں کہ وہ اس کے آگے سر تسلیم خم نہ کرے.پہلی دلیل جو اس معیار کی صداقت کو ثابت کرتی ہے یہ ہے کہ اگر قرآن کریم وہ
یقینی اور قطعی کلام الہی ہے جس میں انسان کا ایک نقطہ یا ایک شعشہ تک دخل نہیں اور وہ اپنے
الفاظ اور معانی کے ساتھ خدا تعالیٰ کا ہی کلام ہے اور کسی فرقہ اسلام کو اس کے ماننے سے
چارہ نہیں.اس کی ایک ایک آیت اعلیٰ درجہ کا تو اتر اپنے ساتھ رکھتی ہے.وہ وحی متلو ہے
جس کے حرف حرف گنے ہوئے ہیں.وہ باعث اپنے اعجاز کے بھی تبدیل اور تحریف سے
محفوظ ہے.لیکن احادیث تو انسانوں کے دخل سے بھری ہوئی ہیں جو ان میں صحیح کہلاتی ہیں
Page 163
160
ان
کا اتنا بھی مرتبہ نہیں جو ایک آیت کے مقابلہ پر ایک کروڑ ان میں سے وہ رنگ اور شان
پیدا کر سکے جو اللہ جل شانہ کی بے مثل کلام کو حاصل ہے.حدیثوں میں ضعف کی وجوہات
اس قدر ہیں کہ ایک دانا آدمی ان پر نظر ڈال کر ہمیشہ اس بات کا محتاج ہوتا ہے کہ ان کو
تقویت دینے کے لئے کم از کم نص قرآنی کا کوئی اشارہ ہی ہو.یہ سچ ہے کہ حدیثیں صحابہ کی
زبان سے بتوسط کئی راویوں کے مؤلفین صحاح تک پہنچتی ہیں اور یہ بھی سچ ہے کہ جہاں تک
ممکن ہے مؤلفین صحاح نے حدیثوں کی تنقید و تفتیش میں بڑی بڑی کوششیں کی ہیں مگر پھر
بھی ہمیں ان پر وہ بھروسہ نہیں کرنا چاہئیے جو اللہ جلشانہ کی کلام پر کیا جاتا ہے.کیونکہ کئی
واسطوں سے اور معمولی انسانوں کے ہاتھوں سے دست و مال ہو کر ائمہ حدیث کو ملی ہیں نہ
خود آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم نے ان کو جمع کرنے یا ان کے لکھوانے کی طرف توجہ فرمائی
نہ صحابہ کرام نے اس کام کو اپنے ذمہ لیا اور نہ خدا تعالیٰ نے احادیث کی حفاظت کا وعدہ فرمایا
جس طرح کہ اس نے قرآن شریف کی حفاظت کا وعدہ فرمایا.علاوہ ازیں احادیث کو جمع
کرنے کا کام آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم کی وفات سے ایک لمبا زمانہ بعد شروع کیا گیا اور
ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں کثرت سے اختلاف اور تناقض پایا جاتا ہے.پس جب قرآن شریف کے مقابل میں احادیث کا یہ حال ہے تو حامیان قتل مرتد
ہمیں خود ہی بتلائیں کہ اگر قرآن شریف اور حدیث میں باہم تعارض اور تناقض نظر آوے
تو پھر ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہئیے ؟ اور قرآن شریف اور حدیث میں سے کس کو
اختیار کریں اور کس کو ترک کریں؟ ایسی صورت میں جو معیار ہم نے پیش کیا ہے وہ یہ ہے
کہ جب قرآن شریف کی آیات اور احادیث میں ہمیں اختلاف نظر آئے تو ہمیں پہلے یہ
کوشش کرنی چاہئیے کہ ان میں باہم تطبیق کی جائے اور احادیث کے ایسے معنے کئے
جاویں جو قرآن شریف کی تعلیم کے مطابق ہوں.اور اگر ہم کسی طرح بھی تطبیق نہ کر سکیں
تو پھر سوائے اس کے اور کوئی چارہ نہیں کہ ہم قرآن شریف کو اختیار کریں اور حدیث کو
Page 164
161
ترک کر دیں کیونکہ قرآن شریف حدیث پر مقدم اور امام ہے.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:.فَبِأَيِّ حَدِيثِ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ (المرسلات : 51)
کہ وہ بتائیں تو سہی کہ اس قرآن کے بعد وہ کس کتاب پر ایمان لائیں گے.اس کے بعد میں حامیان قتل مرتد پر یہ امر بھی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ان کا یہ دعویٰ
بھی غلط ہے کہ یہ طریق دنیا جہان سے نرالا ہے.صحیح البخاری کی کتاب الجنائز میں صاف
لکھا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے حدیث ان الميت يعذب ببعض بكاء اهله
کو قرآن کریم کی آیت لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْری کے معارض
و مخالف پاکر حدیث کی
سیه تاویل کر دی کہ یہ مومنوں کے متعلق نہیں بلکہ کفار کے متعلق ہے جو متعلقین کی جزع فزع
پر راضی تھے بلکہ وصیت کر جاتے تھے.پھر بخاری میں یہ حدیث
لکھی ہے کہ قَالَ هَلْ
وَجَدْتُمُ مَّا وَعَدَكُمْ رَبُّكُمُ حَقًّا.اس حدیث کو حضرت عائشہ صدیقہ نے اس کے
سیدھے اور حقیقی معنے کے رو سے قبول نہیں کیا اس عذر سے کہ یہ قرآن کریم کے معارض
ہے.اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتی اور ابن عمر کی حدیث کو اس
وجہ سے رد کر دیا ہے کہ ایسے معنے معارض قرآن ہیں.ایسا ہی محققوں نے بخاری کی اس
حديث كو كه ما من مولود يو لد الا والشّيطان يمسه حين يولد فيستهلّ
صارخا من مس الشيطان اياه الامريم وابنها قرآن کریم کی ان آیات سے
مخالف پاکر کہ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ وَإِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ
سُلْطن - وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ اس حدیث کی یہ تاویل کر دی کہ ابن مریم اور مریم سے
تمام ایسے اشخاص مراد ہیں جو اُن دونو کی صفت پر ہوں.جیسا کہ ابن حجر نے فتح الباری
شرح صحیح بخاری جلد ۸ صفحہ ۱۵۹ میں لکھا ہے.وقد طعن صاحب الكشاف في معنى هذا الحديث و توقف في
صحته فقال ان صح هذا الحديث فمعناه ان كلّ مولود يطمع
Page 165
162
الشيطان في اغوائه الا مريم وابنها فانهما كانا معصومین و
كذالك من كان في صِفَتِهِمَا لقوله تعالى "إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ
،،
الْمُخْلَصِينَ.“
تلویح میں لکھا ہے.انّما يردّ خبر الواحد من معارضة الكتاب - خبر واحد
جس میں احادیث بخاری و مسلم بھی شامل ہیں بحالت معارضہ کتاب اللہ رڈ کرنے کے
لائق ہے.تفسیر حسینی میں زیر
تغییر آیت وَأَقِيمُوا الصَّلوةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ
لکھا ہے کہ کتاب تیسیر میں شیخ محمد ابن اسلم طوسی سے نقل کیا ہے کہ ایک حدیث مجھے پہنچی
ہے کہ آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کچھ مجھ سے روایت کرو پہلے کتاب اللہ
پر عرض کر لو.اگر وہ حدیث کتاب اللہ کے موافق ہو تو وہ حدیث میری طرف سے ہوگی ورنہ
نہیں.سو میں نے اس حدیث کو کہ مَنْ تَرَكَ الصّلوةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ كَفَرَ قرآن سے
مطابق کرنا چاہا اور تمیں سال اس بارے میں فکر کرتا رہا.مجھے یہ آیت ملی واقیموا الصلوة
ولا تكونوا من المشركين.علماء حنفیہ خبر واحد سے گو وہ بخاری ہو یا مسلم ہو قرآن کریم کے کسی حکم کو ترک نہیں
کرتے.امام شافعی حدیث متواتر کو بھی جن کی تعداد بہت ہی قلیل ہے بمقابلہ آیت کا لعدم
سمجھتے ہیں.اور امام مالک کے نزدیک خبر واحد کے مقابلہ میں قیاس مقدم ہے.پس معلوم ہوا کہ حدیث کو قرآن شریف کی کسوٹی کے ساتھ جانچنے کا اصول دنیا
جہان میں نرالا اصول نہیں ہے بلکہ یہ وہ اصول ہے جس پر مجتہدین امت ہمیشہ عمل کرتے
رہے ہیں.دوسرا عذر جو حامیان قتل مرتد نے قرآن شریف کے معیار سے گریز کرنے کے
لئے پیش کیا ہے یہ ہے کہ امام بخاری جیسے بزرگ کی نسبت یہ خیال بھی دل میں لانا ایک
Page 166
163
حیرت انگیز جرات ہے کہ امام موصوف اپنے مجموعہ میں کوئی ایسی حدیث درج کر سکتے ہیں
جو قرآن مجید کے مخالف ہو.“
اگر چہ یہ عذر حامیان
قتل مرتد نے قرآن شریف کے معیار سے بچنے کے لئے پیش
کیا ہے.مگر اس میں انہوں نے نادانستہ قرآن شریف کو معیار بنانے کے اصول کو جس کو
انہوں نے دنیا جہان سے نرالا اصول قرار دیا تھا درست تسلیم کر لیا ہے کیونکہ ان کے بیان
سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک خود صاحب بخاری نے اس محک سے احادیث کو جانچا
اور صرف انہی احادیث کو اپنی صحیح میں درج کیا جن کو انہوں نے قرآن کے مطابق پایا اور وہ
ہرگز کسی حدیث کو اپنی کتاب میں درج نہیں کر سکتے تھے جس کو اس محک پر جانچنے کے بعد وہ
قرآن شریف کے مخالف پاتے.پس اگر یہ ایسا معیار ہے کہ جس کو خود مؤلف بخاری رحمہ
اللہ علیہ نے احادیث کو جانچنے کے لئے استعمال کیا اور صرف انہی احادیث کو درج کیا جن
کو انہوں نے قرآن شریف کے موافق پایا تو پھر حامیان
قتل مرتد کو اس معیار کے قبول
کرنے میں کیا عذر ہے؟ اور وہ کیوں اس بات کے لئے تیار نہیں کہ ان کی پیش کردہ
روایات کو اسی معیار کے رو سے جانچا جاوے؟
تیسرا عذر جو حامیان قتل مرتد نے قرآن شریف کو معیار قبول کرنے سے گریز
کرنے کے لئے اختیار کرنے کے لئے پیش کیا ہے یہ ہے کہ.یہ خیال کہ جو حدیث صحت و درستی کے مقررہ اور مفید یقین معیار پر پوری اترے
اس کا معارض نص قرآنی ہونا اس کی پذیرائی کے مانع ہے اہل علم کے نزدیک پر کاہ جتنی
وقعت بھی نہیں رکھتا.“
اول تو یہ کہنا کہ جو حدیث صحت و درستی کے مقررہ اور مفید یقین معیار پر پوری
اترے، صحیح نہیں.کیونکہ جس طریق سے احادیث کو جمع کیا گیا ہے اس طریق پر نظر
ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بلا شبہ وہ طریق ظنی ہے اور ان کی نسبت یقین کا ادعا کرنا باطل
Page 167
164
ہے.ائمہ حدیث جس طور سے صحیح اور غیر صحیح حدیثوں میں فرق کرتے ہیں اور جو قاعدہ تنقید
احادیث انہوں نے بنایا ہوا ہے وہ تو ہر ایک پر ظاہر ہے.احادیث صرف راویوں کے
سہارے سے اور ان کی راست گوئی کے اعتبار پر قبول کی گئی ہیں اور یہ طریق یقینی اور قطعی
الثبوت نہیں.ان احادیث کا فی الواقع صحیح اور راست ہونا تمام راویوں کی صداقت اور
نیک چلنی اور سلامت فہم اور سلامت حافظہ اور تقویٰ اور طہارت وغیرہ شرائط پر موقوف ہے.اور ان تمام امور کا کما حقہ اطمینان کے موافق فیصلہ ہونا اور کامل درجہ کے ثبوت پر جو حکم
رؤیت کا رکھتا ہے پہنچنا حکم محال کا رکھتا ہے.اور کسی کی طاقت نہیں کہ حدیثوں کی نسبت ایسا
ثبوت کامل پیش کر سکے.تمام ائمہ حدیثوں کے جمع کرنے میں ایک قسم کا اجتہاد کام میں
لائے اور مجبہتہ کبھی مصیب اور کبھی مخطی بھی ہوتا ہے."
پس حامیان قتل مرتد کا یہ دعوی کہ محدثین کے مقرر کردہ اصول احادیث کو یقین
کے مرتبہ تک پہنچا دیتے ہیں غلط ہے.کیا حامیان
قتل مرتد صحیح بخاری کی تمام احادیث کی نسبت یا ان احادیث کی نسبت
جن کوانہوں نے اپنے دعوای کی تائید میں موجودہ بحث میں پیش کیا ہے حلفاً کہہ سکتے ہیں
کہ ان کا لفظ لفظ یقیناً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات
طیبات ہیں اور ان میں کسی قسم کی تبدیلی اور تغیر نہیں ہوا؟
احادیث کے تین اقسام مقرر کئے گئے ہیں.ایک متواتر.دوم مشہور.سوم احاد.متواتر کی یہ تعریف لکھی ہے.هـو مـا يـرويـه قـوم لا يحصى عددهم ولا
يتوهم تواطؤهم على الكذب لكثرتهم وعدالتهم وتباين اماكنهم ويدوم
هذا الحد الى ان يتصل برسول الله صلعم (حسامی ) یعنی متواتر قسم کی حدیث وہ
ہے جس کے روایت کرنے والے اتنے لوگ ہوں کہ وہ شمار میں بھی نہ آسکیں اور ان کی
تعداد ایسی کثیر ہو اور وہ ایسے عادل ہوں اور ان کے مکان ایک دوسرے سے اس قدر دُور
Page 168
165
ہوں کہ یہ گمان بھی نہ ہو سکے کہ ان سب نے جھوٹ پر اتفاق کر لیا ہے اور یہی شرائط برابران
راویوں کی جماعت میں بھی پائی جائیں جنہوں نے اس حدیث کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
سے روایت کیا.اس قسم کی احادیث کی متعلق کہا گیا ہے کہ یہ علم یقین کا فائدہ دیتی ہیں مگر
ان کی تعداد بہت ہی قلیل ہے.علاوہ ازیں اگر کوئی حدیث تواتر کے درجہ پر بھی ہو، تاہم
قرآن کریم کے تواتر سے اس کو ہرگز مساوات نہیں.دوسری قسم احادیث کی مشہور کہلاتی ہے.اس
کی تعریف لکھی ہے: - هو ما كان
من الاحاد في الاصل ثم انتشر فصار ينقله قوم لا يتوهم تواطؤهم على
الكذب وهم القرن الثانى ومن بعدهم.یعنی دراصل مشہور حدیث بھی احاد میں
سے ہی ہے مگر اس میں اور عام احادیث احاد میں یہ فرق ہے کہ یہ بعد میں یعنی قرن ثانی و
قرن ثالث میں زیادہ لوگوں میں پھیل گئی اور ان بعد کے لوگوں کی تعداد ایسی کثیر ہو کہ ہم یہ
گمان نہ کر سکیں کہ انہوں نے جھوٹ پر اتفاق کر لیا.ان احادیث کا درجہ متواتر سے کم ہے
اور یہ علم یقین کا فائدہ نہیں دیتیں.حسامی میں لکھا ہے کہ لكنه لما كان من الاحاد في
الاصل ثبت به شبهة سقط بها علم الیقین یعنی چونکہ ابتدا میں یہ احادیث بھی
آحاد میں سے ہی تھیں اس لئے ان میں شبہ ثابت ہے اور اس شبہ کی وجہ سے یہ
احادیث یقین کا فائدہ نہیں دیتیں.احادیث کی اس قسم کی نسبت اصول شاشی میں لکھا
ہے فیه ضرب شبهة یعنی اس قسم کی احادیث میں ایک قسم کا شبہ پایا جاتا ہے.تیسری قسم احادیث کی آحاد ہے.اس کی تعریف یہ ہے.خبر الواحد هو ما
نقله واحد عن واحد او واحد عن جماعة او جماعة عن واحد ولا عبرة
للعدد اذا لم تبلغ حد المشهور یعنی خبر واحد وہ ہے جس کو ایک آدمی نے ایک آدمی
سے یا ایک آدمی نے ایک جماعت سے یا ایک جماعت نے ایک آدمی سے نقل کیا ہو اور
کثرت تعداد کا کوئی اعتبار نہیں جب تک کہ وہ مشہور کی کثرت تعداد سے کم ہو.اکثر
Page 169
166
احادیث اسی قسم میں داخل ہیں.یہاں تک کہ صحیح بخاری کی احادیث کا اکثر حصہ بھی احاد کی
قسم سے ہے.اور وہ احادیث بھی جن کو اس بحث میں پیش کیا گیا ہے اس تیسری قسم کی
حدیثوں میں شامل ہیں.اس
قسم کی نسبت اصول شاشی میں لکھا ہے.فیه احتمال شبهة
یعنی ان میں شبہ کا احتمال ہے.اس تقسیم سے صاف ظاہر ہے کہ اکثر احادیث غایت درجہ مفیدطن ہیں اور ظنی نتیجہ
کی منتج ہیں صرف متواتر احادیث کی نسبت یہ کہا گیا ہے کہ وہ مفید یقین ہیں.مگر اول تو ان
کی تعداد بہت ہی قلیل ہے دوسرے وہ بھی ایسی یقینی نہیں جیسا کہ قرآن شریف اور وہ
قرآن شریف کے مقابل میں نہیں رکھی جاسکتیں.اب میں حامیان قتل مرتد کے اس حقارت آمیز دعوی کو لیتا ہوں جس میں وہ بیان
کرتے ہیں کہ یہ خیال کہ جو حدیث صحت و درستی کے مقررہ اور مفید یقین معیار پر پوری
اترے اس کا معارض نص قرآنی ہونا اس کی پذیرائی کے مانع ہے اہلِ علم کے نزدیک پر کاہ
جتنی وقعت بھی نہیں رکھتا.حامیان
قتل مرتد نے اپنے اس بیان میں جو قرآن شریف کی
ہتک کی ہے وہ عیاں ہے.لیکن افسوس ہے کہ ان لوگوں میں ایمانی طاقت ایسی مردہ ہو چکی
ہے کہ ان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ اپنی تحریر میں صرف ان لوگوں کی ہتک نہیں کرتے جو
ہر حال میں قرآن شریف کو مقدم کرتے ہیں اور جن میں حضرت عمر اور حضرت امامِ اعظم
جیسے عظیم الشان انسان شامل ہیں بلکہ خود خدا تعالیٰ کے کلام کی ہتک کرتے ہیں.خیر.مجھے
ان کے احساس سے یہاں کوئی کام نہیں.میں صرف ان کے بیان کا بطلان ظاہر کر دینا
کافی سمجھتا ہوں.امید ہے کہ ائمہ ثلاثہ حامیان قتل مرتد کے نزدیک اہل علم میں شامل
ہوں گے.آؤ.اب ہم دیکھیں کہ یہ بزرگ اس بارے میں کیا رویہ رکھتے ہیں؟
سنئے ! امام شافعی کا یہ مذہب ہے کہ اگر حدیث آیت کے مخالف ہوتو با وجود تواتر
کے بھی کالعدم ہے.امام مالک کے نزدیک خبر واحد کے ساتھ اگر آیت قرآنی کی تصدیق نہ
Page 170
167
ہو تو اس سے قیاس مقدم ہے.علماء حنیفہ خبر واحد سے گووہ بخاری اور مسلم کی ہو قرآن کے
کسی حکم کو ترک نہیں کرتے.علامہ تفتازانی اپنی کتاب تلویح میں لکھتے ہیں.انما خبر الواحد يردّ من معارضة الكتاب واتفق اهل الحق على ان
كتـاب الـلـه مـقـدم على كل قول فَإِنّه كتاب أحكمت آيَاتُهُ لا يَأْتِيهِ
الباطل من بين يديه ولا من خلفه وقد حفظه الله وعصمه وما مسه
ايدى الناس وما اختلط فيه شيء من اقوال المخلوقين
،،
یعنی خبر واحد اگر کتاب اللہ کے معارض ہو تو اسے رد کر دیا جاتا ہے.اور اہل حق کا
اس بات پر اتفاق ہے کہ کتاب اللہ ہر ایک قول پر مقدم ہے.کیونکہ یہ ایسی کتاب ہے جس
میں باطل کو کچھ دخل نہیں اور اللہ جل شانہ نے اس کی حفاظت فرمائی اور اس کو ہر ایک قسم کی
غلطی کی ملاوٹ سے بچایا ہے اور انسانوں کے ہاتھوں نے اس کو نہیں چھوا.اور مخلوقات
کے اقوال میں سے کچھ بھی کتاب اللہ میں داخل نہیں ہوا.اب حامیان
قتل مرتد بتا ئیں.انہوں نے کہاں سے سن لیا کہ اس خیال کی اہلِ علم
کے نزدیک پر کاہ کے برابر بھی وقعت نہیں کہ جو حدیث صحت کے مقرر کردہ کامل معیاروں
پر پوری اترے اس کا معارض نص قرآنی ہونا اس کی پذیرائی کے مانع ہے.کیا صحیح بخاری کی
احادیث جن میں سے اکثر آحاد ہیں صحت کے کامل معیار پر پوری نہیں اترتیں؟ پھر کیا اہل
فقہ ان کو معارض قرآن ہونے کی صورت میں رد نہیں کر دیتے ؟ کیا ائمہ ثلث حامیان قتل
مرتد کے نزدیک اہل علم میں شامل نہیں ؟ کی علامہ تفتازانی اہل علم کے شمار میں نہیں آسکتے ؟
یہ لوگ تو قرآن شریف کو صحیح حدیث پر بھی مقدم رکھتے ہیں اور وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جو
محفوظیت قرآن شریف کی آیات کو حاصل ہے وہ کسی حدیث کو حاصل نہیں اور یہ کہ قرآن
شریف کی آیات میں کسی انسان کا قول داخل نہیں ہوا اور قرآن شریف انسانی دستبرد سے
بالکل محفوظ اور مامون ہے.مگر احادیث کا خواہ وہ صحت کے کیسے اعلیٰ معیار پر ہوں یہ حال
Page 171
168
نہیں ہے.چوتھا عذر حامیان قتل مرتد نے قرآن شریف کے معیار سے گریز کرنے کے لئے یہ
اختیار کیا ہے کہ ہر زید و بکر کے فہم کو فیصلہ کا معیار نہیں مانا جاسکتا.ایک شخص کے نزدیک ایک
حدیث معارض قرآن ہوتی ہے دوسرے کے نزدیک وہ معارض قرآن نہیں ہوتی.اس
اختلاف کی موجودگی میں دواوین حدیث کی کوئی اہمیت نہیں رہتی.چونکہ مرتد کو محض ارتداد کے لئے قتل کرنا ایک ایسا مسئلہ ہے جس کو نہ صرف
قرآن شریف رڈ کرتا ہے بلکہ عقل سلیم بھی اس کو دھکے دیتی ہے.اس لئے حامیان
قتل
مرتد جیسے قرآن شریف کے معیار سے کوسوں دور بھاگتے ہیں.ایسا ہی عقل سلیم کے فتویٰ کا
بھی ان کے دل میں بہت خوف بیٹھا ہوا
ہے اس لئے یہ دونوں سے کنارہ کشی کرتے ہیں.مگر مشکل یہ ہے کہ یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں کہ ان کے بغیر چارہ نہیں.قرآن شریف
چھوڑنے سے تو اسلام کا کچھ باقی نہیں رہتا.اور عقل کو جواب دینے سے خود علماء بے دست و
پا ہو جاتے ہیں کیونکہ اگر عقل کو بالائے طاق رکھ دیا جائے تو تحقیق کا دروازہ بند ہو جاتا
ہے.بیشک ہمارے دین کا دارو مدار سارا قرآن شریف پر ہے اور صحیح احادیث بھی ایک
بیش قیمت خزینہ ہے جو ہماری روح کی غذا ہے اور دین کے سمجھنے میں ہمیں اس سے بڑی
مدد ملتی ہے.اور بہت سی تفاصیل ہیں جو ہمیں احادیث کے ذریعہ حاصل ہوتی ہیں.لیکن
قرآن شریف اور احادیث پر تدبر اور غور کرتے وقت ہمیں عقل سے ہی کام لینا پڑتا ہے.اگر عقل سے کام نہ لیا جاوے تو ایک دم بھی گزارہ نہیں ہوسکتا.خود احادیث صحیحہ میں
اختلاف ہوتا ہے اور اس وقت ہمیں صحیح فیصلہ پر پہنچنے کے لئے عقل کی روشنی کی ضرورت
ہوتی ہے.احادیث اور آیات کا صحیح مفہوم سمجھنے کیلئے ہم کو عقل خدا داد سے کام لینا پڑتا ہے.پس عقل کو جواب نہیں دیا جا سکتا.اگر عقل ایسی گمراہ کن چیز تھی تو ہمیں بار بار قرآن شریف
کی آیات پر تدبر کرنے کی کیوں تاکید کی جاتی ہے؟ حامیان قتل مرتد پوچھتے ہیں کہ
Page 172
169
ہم کسی عقل سے معلوم کریں کہ آیت اور حدیث میں تعارض ہے یا نہیں؟ میں کہتا ہوں کہ
ہم اسی عقل سے معلوم کریں گے جس کے ذریعہ دو متعارض احادیث میں ہم تعارض معلوم
کر سکتے ہیں.اگر ہماری عقل دو متعارض احادیث میں تعارض معلوم کرسکتی ہے تو وہ حدیث
اور آیت میں بھی تعارض معلوم کر سکتی ہے.حامیان قتل مرتد فرماتے ہیں کہ ایک شخص کی
عقل کہتی ہے کہ فلاں حدیث آیت قرآنی کے متعارض ہے اور دوسرے کی عقل کہتی ہے کہ
نہیں کوئی تعارض نہیں اب کس طرح فیصلہ کیا جاوے کہ کس کی عقل درست کہتی ہے اور کسی
کی غلط ہے.میں کہتا ہوں کہ اس کا اسی طرح فیصلہ ہوگا جس طرح کہ ایسے موقعوں پر ہمیشہ
فیصلہ کیا جاتا ہے.دونوں فریق اپنے اپنے دلائل پیش کریں گے اور پبلک خود فیصلہ کر لے
گی کہ کس کے دلائل مضبوط ہیں اور کس کے کمزور ؟
پھر حامیان
قتل مرتد فرماتے ہیں کہ اختلاف رائے کی وجہ سے دواوین حدیث کی
کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی.میں پوچھتا ہوں کہ کیا پہلے اختلاف رائے موجود نہیں ہے؟
پھر کیا اس اختلاف کے ہوتے ہوئے دواوین حدیث کی حیثیت زائل ہوگئی ہے؟ اگر پہلے
اختلاف کی وجہ سے دواوین حدیث کی حیثیت قائم ہے تو پھر بعد کے اختلاف سے بھی ان
کی حیثیت زائل نہیں ہو سکتی.دواوین حدیث تو ایک ذخیرہ ہیں جو تحقیق کے لئے بطور
مصالح کے کام دیتے ہیں.محدثین کا خود اصول ہے کہ اجتہاد کا دروازہ بند نہیں ہوا بلکہ ان
کے نزدیک اجتہاد کا اب بھی حق حاصل ہے.پس اجتہاد اور تحقیق کا باب مسدود نہیں ہوا اور احادیث کو قرآن شریف پر عرض کرنا
یہ بھی ایک تحقیقات کا ذریعہ ہے.اس سے احادیث کا ذخیرہ بے کار نہیں ہو جاتا.کیا جب
دو صحیح احادیث آپس میں متعارض ہوں ایک کو دوسری پر ترجیح نہیں دی جاتی ؟ پھر اگر کوئی
حدیث قرآن شریف کی آیات کے مخالف ہو اور قرآن شریف کو حدیث پر ترجیح دی جائے تو
اس میں دواوین حدیث کی کون سی ہتک لازم آتی ہے؟
Page 173
170
پانچواں عذر قرآن شریف کے معیار سے گریز کرنے کے لئے مولوی صاحبان یہ
پیش کرتے ہیں کہ جو حدیث محدثین کے اصول کے رو سے صحیح ثابت ہو جائے اس کا
معارض قرآن ہونا قطعاً ناممکن ہے.اس لئے کسی ایسی حدیث کو جو محدثین کی اصطلاح میں
صحیح کہلاتی ہے قرآن شریف پر عرض کرنے کی ضرورت نہیں.میں پوچھتا ہوں کہ اگر یہ
درست ہے کہ جس کو محد ثین اپنی اصطلاح میں صحیح حدیث کہتے ہیں وہ قرآن شریف سے
کسی صورت میں بھی معارض نہیں ہو سکتی تو پھر آپ قرآن شریف کا معیار قبول کرنے سے
ڈرتے کیوں ہیں؟ پھر تو آپ کو خوشی سے اس معیار کو قبول کر لینا چاہئے تھا.کیونکہ آپ کے
اس قول سے تو ثابت ہوتا ہے کہ صحیح حدیث کا قرآن سے موافق ہونا ضروری ہے.گویا
آپ اس اصول کو درست تسلیم کرتے ہیں.پس جب یہ اصول خود آپ کے نزدیک بھی
درست ہے تو پھر آپ کیوں میدان میں نہیں نکلتے اور کیوں اپنی پیش کردہ روایات کو ان
معنوں میں جو آپ ان کی طرف منسوب کرتے ہیں قرآن شریف کے ساتھ مطابق کر کے
نہیں دکھاتے ؟
نیز حامیان قتل مرتد کا یہ دعویٰ بھی غلط ہے کہ جس حدیث کا نام محدثین نے اپنے
قواعد کے رو سے صحیح رکھا ہے اس کا معارض قرآن ہونا قطعا ناممکن ہے.جب صحیح کہلانے
والی احادیث خود آپس میں متعارض ہیں تو قرآن شریف سے کیوں متعارض نہیں ہو سکتیں.حامیان
قتل مرتد پہلے ان کا باہمی تعارض دور کریں اس کے بعد یہ دعویٰ پیش کریں کہ ان کا
معارض قرآن ہونا قطعاً ناممکن ہے.ان صحیح کہلانے والی احادیث میں خود با ہم اس قدر
اختلاف ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کا تعارض دور نہیں کر سکے اور ان کی جمع کی
ہوئی احادیث میں جو اصح سمجھی جاتی ہیں اختلاف اور تعارض موجود ہے.اور ان احادیث
میں باہمی سخت تعارض کے ہوتے ہوئے یہ دعویٰ کرنا کہ ان کا معارض قرآن ہونا قطعاً
ناممکن ہے ایک بڑ سے زیادہ حقیقت نہیں رکھتا.
Page 174
171
غرض اس بات میں ذرا بھی شک و شبہ نہیں ہوسکتا کہ قرآن شریف بہر حال
احادیث پر مقدم ہے.قرآن شریف کا ایک ایک حرف اور ایک ایک نقطہ یقینی اور قطعی ہے
اور اس میں انسان کا ذرا بھی دخل نہیں.اور اکثر درجہ احادیث غائت درجہ ظنی ہیں اور
انسان کی دست برد سے خالی نہیں.پس قرآن شریف کا حق ہے کہ اسے حکم بنایا
جاوے.اور اگر کوئی حدیث قرآن کی صریح تعلیم کے خلاف ہو تو اول تو ہمیں اس حدیث کو
ایسے مفہوم میں لینا چاہئیے جو قرآن شریف کے مخالف نہ ہو.اور اگر کوئی صورت تطبیق کی نہ
ہو تو پھر ہمیں قرآن شریف کو حدیث پر مقدم رکھنا چاہئیے نہ کہ اس حدیث کو جو کہ قرآن شریف
کے صریح مخالف ہو.اس لئے موجودہ بحث میں پہلے یہ فیصلہ کرنا ضروری ہے کہ آیا مرتد کا
محض ارتداد کے لئے قتل کرنا قرآن شریف کی تعلیم کے مطابق ہے یا اس کے خلاف ہے؟
اگر قرآن شریف سے قطعی اور یقینی طور پر یہ امر ثابت ہو جائے کہ کسی شخص کو محض اس لئے قتل
کر دینا کہ اس نے اسلام کو ترک کر کے کوئی اور مذہب اختیار کر لیا ہے اسلام کی تعلیم کے
موافق اور مطابق ہے اور قرآن شریف کی تعلیم کی یہی روح ہے کہ ایسے شخص کو قتل کر دینا
چاہئیے جو اسلام لا کر پھر ارتداد اختیار کرتا ہے تو ہمیں بسر و چشم اس عقیدہ کو قبول کرنا چاہیئے
اور اس پر عمل پیرا ہونا چاہئے.لیکن اگر قرآن کریم سے یہ ثابت ہو کہ مرتد کو محض ارتداد کی
وجہ سے قتل کرنا ایک ظلم ہے تو پھر بہر حال قرآن شریف کو مقدم کرنا ہوگا اور اگر کوئی روایت
قرآن شریف کے صریح خلاف ہو تو اسے مجبورا ترک کرنا پڑے گا.عدم قتل مرتد کا ثبوت حدیث سے
اس کے بعد میں نہایت خوشی سے اس بات کا اظہار کرتا ہوں کہ جیسا قرآن شریف
سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مرتد کو محض ارتداد کے لئے قتل کرنا جائز نہیں اسی طرح احادیث
سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم نے کسی مرتد کو محض ارتداد کے لئے قتل
Page 175
172
نہیں کرایا.اور یہ کہ ارتداد کی سزا قتل نہ تھی اور مرتد کے لئے کوئی شرعی سزا مقرر نہیں.یہ
دعوی ہے جس کے ساتھ میں بفضلہ تعالیٰ حدیث کے مضمون کو شروع کرتا ہوں اس دعوی کا
ثبوت حسب ذیل ہے:.پہلا ثبوت.صحیح بخاری میں مندرجہ ذیل واقعہ اس امر کا فیصلہ کر دیتا ہے کہ مرتد
کیلئے محض ارتداد کے واسطے کوئی شرعی حد مقرر نہ تھی.اس حدیث کے اصل الفاظ یہ ہیں.عن جابر بن عبدالله ان اعرابیا بایع رسول الله صلى الله عليه
وسلم على الاسلام فاصاب الاعرابي وعك بالمدينة فجاء
الاعرابى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله
اقلني بيعتي فأبى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم ثم جاء فقال
اقلنی بیعتى ثم جاء ه فقال اقلني بيعتي فأبى فخرج الاعرابي فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم "إنّما المدينة كالكير تنفي خبثها
وتنصع طيبها
(فتح الباری جلد 13 صفحہ 173 و بخاری ہندی صفحہ 1070 )
یعنی جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ ایک اعرابی آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم
کے پاس
آیا اور اسلام پر آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی.اس کے بعد اعرابی کو
مدینہ میں بخار ہو گیا.پھر وہ آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا.اور کہنے لگا کہ میری
بیعت مجھے واپس دے دیں.پھر وہ دوبارہ آیا اور کہنے لگا کہ میری بیعت مجھے واپس دے
دیں.آپ نے انکار فرمایا.پھر وہ اعرابی مدینہ سے چلا گیا.اس پر آنحضرت صلے اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا کہ مدینہ ایک بھٹی کی طرح ہے وہ میل کو نکال دیتا ہے اور اصل پاکیزہ چیز کو
خالص کر دیتا ہے.اب بیدار تعداد کا واقعہ ہے جو مدینہ میں واقع ہوا.ایک شخص اسلام لانے کے بعد
Page 176
173
مرتد ہو گیا مگر اس کو قتل کی سزا نہیں دی گئی.اب کہاں ہیں حامیان
قتل مرتد ؟ وہ بتائیں کہ
اگر اسلام میں ارتداد کے لئے قتل کی حد مقررتھی تو پھر اس مرتد کو کیوں
قتل نہ کیا گیا؟ اس پر
کیوں شرعی حد جاری نہ کی گئی ؟ کیا امیر امان اللہ خان کو آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم کی نسبت
زیادہ دینی غیرت ہے؟ کیا امیر کا بل آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم کی نسبت شرعی حدود کا
زیادہ نافذ کرنے والا ہے؟ پھر کیا وجہ کہ اس مرتد کو جس نے آپ کے سامنے مدینہ میں
ارتداد کیا قتل نہ کیا گیا؟ اس شخص کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بار بار آنا بھی ظاہر
کرتا ہے کہ مرتد کے لئے قتل کی سزا مقرر نہ تھی.اور نہ وہ کبھی آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم کے
پاس نہ آتا بلکہ کوشش کرتا کہ بلا اطلاع چپکے سے نکل جائے اور کسی پر ظاہر نہ کرتا کہ وہ ارتداد
اختیار کرنا چاہتا ہے.ہمیں بتایا جاتا ہے کہ مرتد کی سزا قتل، ارتداد کو روکنے کے لئے شریعت اسلام میں
مقرر کی گئی ہے اور اس کی غرض و غایت یہ ہے کہ لوگوں کو اسلام پر رہنے کے لئے مجبور کیا
جائے.اگر یہ بات سچ ہے تو آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم نے کیوں اس کو متنبہ نہ کیا ؟ اور
کیوں یہ نہ کہا کہ یاد رکھو! کہ اسلام میں ارتداد کی سزا قتل ہے.اگر تم ارتداد اختیار کرو گے تو
تمہیں قتل کیا جائے گا؟ اور جب کہ وہ بار بار ارتداد کا ارادہ ظاہر کرتا تھا اور خوف تھا کہ وہ
مرتد ہو کر چلا جائے گا تو ایسی صورت میں کیوں اس پر پہرہ مقرر نہ کیا گیا تا اگروہ مرتد ہوکر
جانے لگے تو اس کو پکڑ لیا جاوے اور اس پر شرعی حد جاری کی جاوے؟ کیوں صحابہ نے اس
کو یہ نہ کہا کہ میاں! اگر جان کی خیر چاہتے ہو تو ارتداد کا نام نہ لو کیونکہ اس شہر میں تو یہ قاعدہ
جاری ہے کہ جو شخص اسلام لا کر پھر ارتداد اختیار کرتا ہے اس کو فورا قتل کر دیا جاتا ہے؟
پس اس اعرابی کا بار بار ارتداد کا اظہار کرنا اور اس کا آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم
کے پاس بار بار جانا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو ارتداد کے نتیجہ سے متنبہ نہ کرنا اور
نہ صحابہ کا اس کو قتل کا حکم سنانا اور آخر کار اس کا بغیر کسی قسم کے تعرض کے مدینہ سے نکل جانا،
Page 177
174
یہ سب امور صاف طور پر اس امر کے شاہد تین ہیں کہ اسلام میں مرتد کے لئے کوئی شرعی حد
مقرر نہ تھی.پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے نکل جانے پر ایک طرح کی خوشی کا اظہار
کرنا اور فرمانا کہ مدینہ ایک بھٹی کی طرح ہے جو میل کچیل کو پاکیزہ جوہر سے جدا کر دیتا ہے
صاف ظاہر کرتا ہے کہ آپ اس اصول کے مخالف تھے کہ کسی کو جبر سے اسلام پر رکھا جاوے
اور لوگوں کو جبری ذرائع اختیار کر کے ارتداد سے روکا جائے.بلکہ اگر ناپاک انسان
مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہو جاتا تو آپ اس پر نا خوش نہیں ہوتے تھے.اور آپ یہ
کوشش نہیں فرماتے تھے کہ اس کو اس کی مرضی کے خلاف جبراً اسلام میں رکھا جاوے بلکہ
ایسے شخص کا چلا جانا آپ کے نزدیک گویا خس کم جہاں پاک کا مصداق تھا.اگر آپ کا یہ
اصول ہوتا کہ جو شخص ایک دفعہ اسلام میں داخل ہو جائے اس کو ہر ممکن ذریعہ سے اسلام
میں رہنے کے لئے مجبور کیا جائے.اور اگر وہ کسی طرح بھی نہ مانے تو اس کو قتل کیا جاوے
تا اس کی مثال دوسروں کے لئے عبرت ہو.تو چاہئیے تھا کہ آپ اس اعرابی کے جانے پر خفا
ہوتے اور صحابہ کو ڈانٹتے کہ تم نے اس کو کیوں جانے دیا ؟ کیوں اس کو پکڑ کر قتل کی دھمکی نہ
دی؟ اور چاہیے تھا کہ آپ صحابہ کو حکم دیتے کہ دوڑو! اور جہاں ہو اس خبیث کو پکڑ لاؤ
تا اس کو قتل کی سزا دی جائے.مگر آپ نے ایسا نہ کیا بلکہ دوسرے الفاظ میں یہ فرمایا کہ اچھا
ہوا وہ چلا گیا.وہ اس قابل نہ تھا کہ مسلمانوں میں رہے.خدا تعالیٰ نے خود اس کو اپنے ہاتھ
سے ہم سے جدا کر دیا ہے.غرض اس اعرابی کی مثال ایک قطعی اور یقینی ثبوت اس امر کا ہے کہ مرتد کے لئے
کوئی شرعی سزا مقرر نہ تھی اور مسلمانوں میں قطعاً یہ طریق جاری نہ تھا کہ وہ ہر ایک مرتد کو
محض اس کے ارتداد کی وجہ سے قتل کر دیتے.دوسرا ثبوت اس امر کا کہ مرتد کے لئے کوئی شرعی حد مقرر نہ تھی وہ شرائط ہیں جن
Page 178
175
کے ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام حدیبیہ میں مشرکین مکہ کے ساتھ صلح کی صلح
حدیبیہ کی حدیث میں لکھا ہے.صالح النبي صلى الله عليه وسلم المشركين يوم الحديبية على
ثلاثة اشياء على من اتاه من المشركين رده اليهم ومن اتاهم من
المسلمين لم يردّوه.بخاری) مطبوعه مصر جلد 2 صفحه 76)
براء بن عازب سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے دن
مشرکین کے ساتھ تین باتوں پر صلح کی.پہلی شرط یہ تھی کہ اگر مشرکین سے کوئی شخص مسلمان
ہو کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے تو آپ اس کو مشرکین کی طرف واپس کر
دیں گے.دوسری شرط یہ تھی کہ اگر مسلمانوں میں سے کوئی شخص مرتد ہو کر مشرکین کی طرف
چلا جائے تو مشرکین اس کو آپ کی طرف واپس نہیں کریں گے.اس صلح نامہ کی دوسری شرط سے صاف طور پر ظاہر ہوتا ہے کہ مرتد کے لئے کوئی شرعی
حد مقرر نہ تھی کیونکہ اگر ارتداد کے لئے شریعت اسلام میں یہ سزا مقرر ہوتی کہ اس کو قتل کیا
جائے تو شرعی حد کے معاملہ میں کبھی مشرکین کی بات قبول نہ فرماتے.اس صلح کی نسبت خود
خدا تعالیٰ شہادت دیتا ہے کہ اس کے شرائط تقویٰ پر مبنی تھے.چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:.إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللهُ
سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ
بِهَا وَ أَهْلَهَا وَكَانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (الفتح:27)
اس وقت کو یاد کرو جبکہ کافروں نے اپنے دلوں میں ایسی جذبہ داری کی روح پھونکی جو
جاہلیت کی جنبہ داری کی روح تھی.اس پر اللہ نے اپنی طرف سے نازل ہونے والی
سکینت اپنے رسول کے دل پر اور مومنوں کے دل پر اُتار دی اور تقویٰ کے طریق پران
کے قدم کو مضبوط کر دیا اور وہی اس کے زیادہ مستحق تھے اور اس کے اہل تھے اور اللہ ہر
Page 179
176
ایک چیز کو جانتا ہے.پس آپ کا اس امر کو منظور فرما لینا کہ اگر کوئی شخص مسلمانوں میں سے مرتد ہوکر
مشرکین کی طرف چلا جائے گا تو اس کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا صاف طور پر ظاہر کرتا ہے
کہ مرتدین کے لئے کوئی شرعی حد مقرر نہ تھی.ورنہ آپ فرماتے کہ یہ شرعی حد کا معاملہ ہے
اور میں شرعی حکم کے خلاف تمہارے ساتھ معاہدہ نہیں کر سکتا کیونکہ یہ تقویٰ کے خلاف
ہے.شرعی حدود کے اجراء کے معاملہ میں آپ ایسے مضبوط تھے کہ اس کے خلاف آپ کسی
کی بات سننے کے لئے تیار نہ تھے.پھر کس طرح ممکن ہے کہ شرعی مجرموں کے متعلق آپ
کوئی ایسی شرط منظور فرماتے جو شرعی احکام کے نفاذ میں روک ہو.اگر کوئی شخص یہ عذر
کرے کہ ایسا شخص مکہ میں جا کر شرعی حدود کے دائرہ سے نکل جاتا تھا کیونکہ وہ اسلامی
علاقہ سے نکل کر دشمن کے علاقہ میں چلا جاتا تھا تو یہ عذر درست نہیں ہے.کیونکہ دشمن کا
ملک وہ اس وقت کہلا سکتا تھا جب تک کہ صلح نہیں ہوئی تھی.مصالحت کے بعد وہ علاقہ
دشمن کا علاقہ نہیں کہلا سکتا تھا.ایسا عذر کرنے والا مجھے انصاف سے بتائے کہ اگر مشرکین
ملکہ کسی اور شرعی مجرم کی نسبت یہ شرط کرتے کہ اگر وہ ہمارے علاقہ میں آجائے تو اس پر
شرعی حد جاری نہ کی جائے.تو کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے اس شرط کو منظور
فرمالیتے کہ ایسا مجرم دشمن کے علاقہ میں چلا جانے کی وجہ سے اسلامی احکام کے دائرہ سے
خارج ہو جاتا ہے اس لئے ایسی شرط منظور کرنے میں کوئی حرج نہیں.میں یقین کرتا ہوں کہ
ہر ایک انصاف پسند یہی کہے گا کہ آپ کسی اور شرعی مجرم کے متعلق ایسی شرط ہرگز قبول نہ
فرماتے.پھر کیا وجہ ہے کہ آپ نے مرتد کے متعلق ایسی شرط منظور فرمالی ؟ اگر ارتداد کے لئے
بھی ایسی ہی شرعی حد مقرر ہوتی جیسی کہ مثلا قتل یا سرقہ باز نا کے لئے حد مقرر ہے تو آپ کبھی
صلح نامہ کی دوسری شرط منظور نہ فرماتے.پس آپ کا اس شرط کو قبول کر لینا اس امر کا تین
ثبوت ہے کہ ارتداد شرعی جرم نہیں سمجھا جاتا تھا اور اس کے لئے کوئی شرعی حد مقرر نہ تھی.
Page 180
177
تاریخ سے یہ بھی ثابت ہے کہ صحابہ کو یہ صلح بہت دوبھر معلوم ہوئی کیونکہ اس میں
وہ اپنی سیکی سمجھتے تھے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس صلح کی شرائط
پر اعتراض کیا.اور اگر شریعت اسلام میں یہ بھی حکم ہوتا کہ مرتد پر قتل کی حد جاری کی جائے تو
جہاں صحابہ نے اپنے دوسرے اعتراض پیش کئے وہ یہ بھی عرض کرتے کہ مرتد کے لئے تو
شریعت اسلام کا یہ حکم ہے کہ اس پر قتل کی حد جاری کی جائے اس کے متعلق آپ کیوں ایسی
شرط منظور فرماتے ہیں؟ مگر انہوں نے ایسا اعتراض نہیں کیا جس سے ظاہر ہے کہ شریعت
اسلام میں مرتد کے لئے کوئی شرعی حد مقرر نہ تھی.تیسرا ثبوت.تیسرا ثبوت اس امر کا اسلام میں مرتد کے لئے قتل کی سزا مقررنہ
تھی وہ مکالمہ ہے جو ابوسفیان اور ہر قل کے درمیان مقام ایکیا میں ان ایام میں ہوا جب کہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین مکہ کے مابین صلح ہو چکی تھی یعنی صلح حدیبیہ کے بعد.ابوسفیان خود اس سوال و جواب کا ذکر کرتا ہے جو ہر قل قیصر روم اور اس کے مابین واقع ہوا
وہ کہتا ہے کہ جب ہر قل نے مجھے اپنے دربار میں بلایا تو میرے ساتھیوں کو میرے پیچھے
کھڑا کر دیا اور ان کو کہا کہ میں اس شخص کے بارے میں جو تمہارے ملک میں نبوت کا
دعوی کرتا ہے تمہارے اس ساتھی (ابوسفیان ) سے کچھ سوال کروں گا.اگر یہ شخص اپنے
جواب میں کوئی بات خلاف واقعہ بیان کرے تو تم اس کی فور تردید کر دینا.ابوسفیان کہتا
ہے کہ اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ اگر میں جھوٹ کہوں
گا تو میرے ساتھی میری تردید کر دیں
گے اور اس طرح مجھے اس بادشاہ کے دربار میں شرمندہ ہونا پڑے گا تو میں اپنے جوابات
میں ضرور جھوٹ سے کام لیتا.اور میں نے بہت کوشش کی کہ میں اپنے جوابات میں کوئی
ایسی بات بھی ملا دوں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو.مگر مجھے کوئی ایسا موقع نہ
ملا.سوائے ایک بات کے اور وہ یہ تھی کہ جب اس نے مجھ سے سوال کیا کہ یہ نبی اپنے عہد
میں کیسا ہے؟ تو میں نے جواب دیا کہ اب تک تو اس نے ہمارے ساتھ کوئی عہد شکنی نہیں
Page 181
178
کی.ہاں اب ایک تازہ معاہدہ اس سے ہوا ہے دیکھئے اب وہ کیسا معاملہ کرتا ہے؟ اپنے
عہد پر قائم رہتا ہے یا نہیں.ابوسفیان کہتا ہے کہ صرف یہ الفاظ تھے جو میں اپنے جوابات
میں اپنی طرف سے بڑھا سکا.اور کوئی موقع مجھے ایسا نہ ملا کہ میں کوئی ایسی بات کہہ سکوں جو
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پڑے.اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو سوالات ہر قل قیصر روم نے اپنے دربار میں ابوسفیان سے
کئے ان میں ایک سوال ارتداد کے متعلق بھی تھا.ہر قل نے ابوسفیان سے سوال کیا کہ لوگ
اس نبی کا دین قبول کرنے کے بعد مرتد ہوتے ہیں یا نہیں ؟ تو اس نے جواب دیا کہ نہیں.اب اگر یہ واقعہ ہے کہ ارتداد کے روکنے کے لئے آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دے
رکھا تھا کہ ہر ایک شخص جو اسلام لانے کے بعد ارتداد اختیار کرے اس کو قتل کردو تو ابوسفیان
ضرور اس امر کا ذکر ہر قتل سے کرتا.وہ تو اس تاڑ میں لگا ہوا تھا کہ کوئی مفید مطلب بات مجھے
مل جائے تو میں اسے بیان کروں.بھلا وہ ایسے موقع کو کیوں اپنے ہاتھ سے جانے دیتا.وہ
ضرور کہتا کہ ہاں صاحب! مرتد تو نہیں ہوتے مگر اس کی یہ وجہ ہے کہ اس نے حکم دے رکھا
ہے کہ جو شخص اس کے دین سے ارتداد اختیار کرے گا اس کو قتل کیا جائے گا.پس ہر قل قیصر روم کے ساتھ ابوسفیان کا تاریخی مکالمہ بھی اس امر کی ایک قوی
دلیل ہے کہ ارتداد کے لئے مرتدین کو قتل کرنے کا کوئی حکم اسلام میں جاری نہ تھا.چوتھا ثبوت.میں خدا تعالی کا ہزار شکر کرتا ہوں کہ اس نے اپنے فضل اور رحم
سے اس دعوی کے پاش پاش کرنے کے لئے اسلام میں مرتد کے لئے قتل کے لئے شرعی
حد مقرر کی گئی ہے ایک ایسا حربہ عطا فرمایا ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی کاری حربہ خیال میں
لانا بھی مشکل ہے.یہ ایسا تیز حربہ ہے کہ اس کے سامنے قتل مرتد کا عقیدہ ایک طرفۃ العین
کے لئے بھی ٹھہر نہیں سکتا.ان زبر دست دلائل میں سے ایک دلیل جو اس غلط عقیدہ کو اس طرح اڑا دیتی ہے
Page 182
179
جس طرح کہ ایک تنکا تیز ہوا کے سامنے اُڑ جاتا ہے میں ذیل میں پیش کرتا ہوں.اور
ناظرین کو معلوم ہوگا کہ کس طرح وہ واقعہ جس کو میں ابھی بیان کروں گا روز روشن کی طرح
اس امر کو ثابت کر دیتا ہے اور اس میں ذرہ بھی شک نہیں رہتا کہ ارتداد کے لئے اسلام میں
کوئی شرعی حد مقرر نہیں کی گئی.یہ واقعہ عبداللہ بن ابی سرح کا ہے.وہ مدینہ میں آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم کا
کاتب وحی تھا مرتد ہو کر کفار سے جاملا.فتح مکہ کے وقت آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم نے
سب کو معافی دے دی سوائے چند آدمیوں کے جن کی تعداد دس بارہ سے زیادہ نہ تھی.ان
چند آدمیوں کی نسبت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کا حکم دیا.ان میں عبد اللہ بن ابی
سرح کا نام بھی تھا.یہ حضرت عثمان بن عفان کا رضاعی بھائی تھا.حضرت عثمان نے اس کو
اپنے ہاں پناہ دے دی اور وہ ان کے گھر میں چھپا رہا.جب امن ہو گیا تو حضرت عثمان
نے اس کی سفارش کی.ان کی سفارش پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک خاموش رہے.اس کے بعد آپ نے اس کو معاف کر دیا.جب عبد اللہ بن ابی سرح چلا گیا تو آپ نے صحابہ کو فرمایا کہ جب میں نے معافی
دینے میں دیر کی تھی تو تم نے اس کو قتل کیوں نہ کر دیا ؟ صحابہ نے عرض کیا.آپ اشارہ فرما
دیتے تو ہم اس
کو قتل کر دیتے.آپ نے فرمایا وان الـنـبـي لا ينبغي ان تكون لـه
خائنة الاعین“ یعنی یہ نبی کی شان سے بعید ہے کہ وہ آنکھوں کی خیانت سے کام لے.تفسیر کبیر میں عبداللہ بن ابی سرح کی نسبت لکھا ہے.فلـمـا كـان يـوم الفتح امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله
فـاسـتـجـارلـه عثمان فأجاره رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انه
اسلم وحسن اسلامه
( تفسیر کبیر لفخر الدین رازی جلد 5 صفحہ 527)
Page 183
180
یعنی فتح کے دن آپ نے عبد اللہ بن ابی سرح کے قتل کا حکم دیا.حضرت عثمان نے اس کو
اپنی پناہ میں لے لیا.اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو پناہ دے دی اور
معاف کر دیا.روح المعانی جلد ۴ صفحہ ۴ ۴۸ پر لکھا ہے.كان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فازله الشيطن فلحق
بالكفّار فامر به النبي صلى الله عليه وسلم ان يقتل يوم فتح مكة
فاستجارله عثمان بن عفان رضی الله عنه فاجاره النبي صلى
عليه وسلم."
الله
یعنی وہ پہلے کاتب وحی تھا.پھر شیطان نے اس
کو بہکا دیا اور وہ کافروں سے جاملا.فتح مکہ
کے دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کا حکم دیا.حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے
اس کو اپنی پناہ میں لے لیا.پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو پناہ دے دی.اب عبد اللہ بن ابی سرح کا واقعہ صاف طور پر ظاہر کرتا ہے کہ اسلام میں ارتداد کے
لئے کوئی شرعی حد مقرر نہیں کی گئی.اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد اللہ بن ابی سرح
کے قتل کا حکم اس لئے نہیں دیا تھا کہ وہ مرتد تھا بلکہ اس لئے کہ وہ ایک پولیٹیکل مجرم تھا.کیونکہ (۱) حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا عبد اللہ بن ابی سرح کو اپنے گھر میں پناہ
دینا بھی ظاہر کرتا ہے کہ اس کو پولیٹیکل جرم کی وجہ سے قتل کا حکم دیا گیا تھانہ ارتداد کی وجہ
سے.کیونکہ اگر قتل کے حکم کی وجہ ارتداد ہوتا اور ارتداد کے لئے قتل شرعی حد ہوتی تو حضرت
عثمان کبھی اس کو شرعی حد سے بچانے کے لئے کوشش نہ کرتے.کیا ناظرین خیال کر سکتے ہیں کہ مثلاً ایک شخص زنا کا ارتکاب کرتا یا سرقہ کا مرتکب
ہوتا تو حضرت عثمان ایسے شخص کو شرعی حد سے بچانے کے لئے اپنے ہاں پناہ دیتے؟ ہرگز
نہیں.پس اگر عبد اللہ بن ابی سرح کو ارتداد کی وجہ سے قتل کا حکم دیا گیا تھا اور ارتداد کیلئے
Page 184
181
شرعی حدقتل مقرر تھی تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جیسا انسان کبھی ایسے شخص کو شرعی حد سے
بچانے کے لئے اپنے گھر میں پناہ نہ دیتا اور کبھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ
سفارش نہ کرتے کہ اس مرتد پر شرعی حد جاری نہ کی جائے.(۲) اگر فرض بھی کر لیا جائے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے یہ غلطی ہوئی کہ
انہوں نے ایک ایسے شخص کو اپنے ہاں پناہ دی جو ایک شرعی حد کا سزاوار ہو چکا تھا اور اس کو
شرعی حد سے بچانے کے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کی سفارش کی.تو یہ
کبھی بھی گمان میں نہیں آسکتا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم شرعی حد کے متعلق کسی کی بھی
سفارش قبول فرماتے.یہ ایک ثابت شدہ اور یقینی امر ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
شرعی حد کے نفاذ کے وقت کسی کی بھی سفارش نہیں سنتے تھے اور اگر کوئی شخص کسی ایسے مجرم کی
سفارش کرتا جس پر شریعت کی حدوارد ہوتی تو ایسے سفارش کرنے والے پر بھی آپ ناراض
ہوتے.اس مخزومی عورت کا واقعہ یاد کرو جس نے چوری کا ارتکاب کیا.میں یہاں اس
واقعہ کو حضرت عائشہؓ کے الفاظ میں صحیح بخاری سے نقل کرتا ہوں:.عن عائشة ان قريشا اهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت قالوا
من يكلم رسول صلى الله عليه وسلم و من يجترئ اليه الا اسامة ابن
زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلم رسول الله صلى
الله عليه وسلم فقال أتشفع فى حد من حدود الله ثم قام فخطب
فقال ايها الناس انّما ضلّ من قبلكم انهم كانوا اذا سرق الشريف
تركوه واذا سرق الضعيف فيهم اقاموا عليه الحد وأيم الله لو ان
فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم) سرقت لقطعت يدها.( بخاری ہندی صفحہ 1003 )
"
یعنی قریش کو اس مخزومی عورت کی وجہ سے بہت فکر ہوا جس نے چوری کی تھی.انہوں
Page 185
182
نے آپس میں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کون بات کر سکتا ہے اور کس کو آپ
سے گفتگو کرنے کی جرات ہو سکتی ہے سوائے اسامہ بن زیڈ کے جس کے ساتھ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کومحبت ہے.پس حضرت اسامہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
سے اس بارہ میں سفارش کی.آپ نے فرمایا أتشفع في حدٍ من حدود الله کیا تو
خدا تعالیٰ کی حدود میں سے ایک حد کے بارے میں سفارش کرتا ہے؟ پھر آپ کھڑے
ہوئے.آپ نے ایک تقریر فرمائی.اور سب صحابہ کو مخاطب ہو کر فرمایا.اے لوگو! تم
سے پہلی امتیں اس لئے گمراہ ہو گئیں کہ جب کوئی شریف خاندان کا آدمی ان میں سے
چوری کرتا تو اس کو چھوڑ دیتے اور جب کوئی کمزور آدمی چوری کرتا تو اس پر شرعی حد جاری
کرتے.خدا تعالیٰ کی قسم ! اگر فاطمہ بنت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) چوری کرتی تو میں اس
کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا.اس واقعہ سے ناظرین نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم کا شرعی حدود
کے معاملہ میں کیا رویہ تھا.کیا ناظرین ایک طرفہ العین کے لئے بھی گمان کر سکتے ہیں کہ
حضرت
عثمان یا کسی اور شخص کی سفارش پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی شرعی حد کو ترک کر سکتے
تھے ؟ اگر عبداللہ بن ابی سرح پر بوجہ ارتداد کوئی شرعی حد وارد ہو سکتی تھی تو یہ کس طرح ممکن تھا کہ
آپ حضرت عثمان کی سفارش کا لحاظ کر کے اس کو معاف کر دیتے.لکھا ہے کہ حضرت عثمان کی
سفارش پر دیر تک آپ خاموش رہے اور اس خیال پر کہ صحابہ میں سے کوئی شخص اسے تلوار کی
گھاٹ اتار دے گا.اگر عبداللہ ابن ابی سرح ایک شرعی حد کا مستوجب تھا تو آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کو کیا ضرورت تھی کہ اس طرح خاموشی اختیار کرتے اور صحابہ کا انتظار فرماتے کہ ان
میں سے کوئی شخص عبد اللہ بن ابی سرح کو قتل کرتا؟ ایسی صورت میں آپ حضرت عثمان کو
وہی جواب دیتے جو آپ نے اسامہ کو دیا تھا.اتشفع في حد من حدود الله یعنی کیا
تو حدود اللہ کے متعلق سفارش کرتا ہے؟ آپ اس قسم کی سفارشوں کو سخت کراہت کی نظر سے
Page 186
183
دیکھتے تھے اور آپ نے مخزومی عورت کے واقعہ میں صحابہ کے سامنے اس مضمون پر ایک
خاص تقریر فرمائی اور ان کو متنبہ کیا کہ شرعی حدود کے اجراء میں کسی شخص کے ساتھ رعایت
کرنا ہلاکت کی راہ ہے اس سے ہمیشہ بچتے رہو.تم سے پہلی قومیں اسی وجہ سے ہلاک
ہوئیں.ایسا نہ ہو کہ تم بھی یہی طریق اختیار کر کے ہلاک ہو جاؤ.پس جس امر سے آپ نے لوگوں کو ایسی سختی سے ڈرایا یہ کس طرح گمان میں آسکتا
ہے کہ آپ نے خود وہی کام کیا؟ اور نہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی نسبت یہ گمان ہو سکتا ہے
کہ انہوں نے ایسی جرات کی کہ ایک شرعی مجرم کو شریعت کی حد سے بچانے کے لئے اپنے
گھر میں کئی دن تک چھپائے رکھا اور پھر اس کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے
سفارش کی کہ اس پر شرعی حد جاری نہ کی جائے.پس حضرت عثمان کا عبد اللہ بن ابی سرح کو
اپنے ہاں پناہ دینا اور پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کرنا اور آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کا باوجود نا پسندیدگی کے محض عثمان کی پاس خاطر اس کو معاف کر دینا صاف ظاہر کرتا
ہے کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد اللہ بن ابی سرح کے قتل کا حکم اس کے ارتداد کی سزا
میں نہیں دیا تھا اس کے متعلق بھی اس حکم کی اسی قسم کی وجوہات تھیں جو اس کے ساتھ کے
دوسرے دس بارہ آدمیوں کی صورت میں تھیں.آپ نے صرف عبد اللہ بن ابی سرح کے
قتل کا حکم نہیں دیا تھا بلکہ ان کے ساتھ بعض اور آدمی بھی تھے جن کے متعلق آپ نے ایسا ہی
حکم دیا تھا مگر ان میں سے صرف چار ہی مارے گئے باقی سب کو عبد اللہ بن ابی سرح کی
طرح معافی دے دی گئی.میں ان کی فہرست ذیل میں نقل کرتا ہوں تا ناظرین کو معلوم ہو
کہ اس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے متعلق قتل کا حکم ارتداد کی وجہ سے نہ تھا بلکہ
ان کے دوسرے جرموں کی وجہ سے تھا.(۱) ابن خطل.مسلمان ہونے کے بعد ایک صحابی کو قتل کر کے بھاگ آیا تھا.آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم کی ہجو میں شعر کہا کرتا تھا اور اپنی لونڈیوں سے آنحضرت صلی اللہ
Page 187
184
علیہ وسلم کی ہجو میں شعر کہلوا کر لوگوں کو سنوایا کرتا تھا.مسلمانوں کو ہر طرح دکھ دیتا تھا.اس کو
قتل کیا گیا.شرح زرقانی علی مواہب اللہ نیہ جلد 2 صفحہ 322)
(۳۲) ابن خطل کی دولونڈیاں جو آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم کی ہجو میں
شعر کہہ کر لوگوں میں مشہور کیا کرتی تھیں.(ایضاً جلد 2 صفحہ 314) ایک نے معافی
حاصل کر لی دوسری کو قتل کر دیا گیا.(۴) عکرمہ بن ابی جہل.اپنے باپ کی زندگی میں اور اس کے بعد مسلمانوں
سے لڑتا رہا.فتح مکہ کے وقت مسلمانوں پر حملہ کیا.فتح مکہ کے بعد اطاعت اختیار نہ کی بلکہ
بھاگ گیا.اس کی بیوی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے لئے معافی حاصل کی.(۵) حویرث بن نقید.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت ہجو کیا کرتا تھا اور
اشعار بناتا تھا.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دولڑ کیوں فاطمہ اور ام کلثوم کو حضرت عباس
اپنے ساتھ مدینہ لے جارہے تھے.حویرث بن نقید نے اونٹ کو نیزہ مار کر لڑکیوں کو نیچے گرا
دیا.ہبار بن الاسود جس نے حضرت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ کو نیزہ
مارکر حضرت زینب کو زمین پر گرایا اس کے ساتھ یہ بھی شریک تھا.جو سیرت کو قتل کیا گیا.شرح زرقانی علی مواہب اللدنیہ جلد 2 صفحہ 315)
(1) مقیس بن صبابہ.یہ شخص ایک انصاری کو قتل کر کے بھاگ آیا تھا اور مرتد
ہو گیا تھا.اس
کو قتل کیا گیا.(۷) ہبار بن الاسود.اس نے حضرت زینب کو ہجرت کے وقت اونٹ سے
ایک چٹان پر گرایا جس کی وجہ سے ان کا اسقاط ہو گیا.اس کو بعد میں معاف کر دیا گیا.(۸) کعب بن زہیر.نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اشعار میں ہجو کر تا تھا.اس کو
بعد میں معافی دے دی گئی.(۹) ہندہ بنت عتبہ زوجہ ابو سفیان.جس نے حضرت حمزہ کا مثلہ کیا.کلیجہ
Page 188
185
نکال کر دانتوں میں چبایا اور ان کے بدن کے ٹکڑوں کے ہار بنا کر بازوؤں اور پاؤں پر
پہنے.اس کو بھی بعد میں معافی دے دی گئی.(۱۰) وحشی بن حرب.ہندہ بنت عتبہ کا غلام.اس نے ہندہ کے کہنے پر
حضرت حمزہ کو شہید کیا.اس کو بھی معافی دے دی گئی.مندرجہ بالا فہرست سے ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ ان میں ایک بھی ایسا نہ تھا جس کی
نسبت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارتداد کے لئے قتل کا حکم دیا.اس فہرست میں دو مرتد
بھی شامل ہیں مگر ارتداد کے جرم کی وجہ سے ان کی نسبت قتل کا حکم نہیں دیا گیا.بلکہ ان کے
دوسرے جرموں کی وجہ سے.اور یہ سب مفسد لوگ تھے.بعض ان میں سے قاتل تھے.بعض آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت عناد رکھنے والے اور لوگوں کو آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کے خلاف ہجو آمیز شعروں کے ذریعہ اکسانے والے تھے.یہ سب لوگ اپنے
رویہ سے واجب القتل تھے.مگر پھر بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال رحم دلی سے
اکثر کو معاف کر دیا.صرف چار کو قتل کیا جن میں سے دو قاتل تھے.تیسری ایک مفسدہ
عورت تھی جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہجو کے شعر کہ کولوگوں کو اکساتی تھی.چوتھا بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو کرنے والا.لوگوں میں شر پھیلانے والا اور مفسد
تھا.اور اس نے دو دفعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑکیوں کو ہجرت کے وقت اونٹ سے
گرانے کا ارتکاب کیا.ان چاروں کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی حاصل کرنے کا
موقع نہیں ملا.اور مختلف موقعوں پر صحابہ کے ہاتھوں سے قتل کئے گئے.اگر ان کو بھی معافی
مانگنے کا موقع مل جاتا تو ممکن تھا کہ اگر سب کو نہیں تو کم از کم بعض کو ان میں سے اسی طرح
معافی مل جاتی جس طرح کہ ان کے باقی ساتھیوں
کو مل گئی تھی.دو آدمیوں کی نسبت لکھا ہے کہ ام ہانی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آکر
عرض کی کہ میں نے ان کو پناہ دی ہے مگر علی ان
کو قتل کرنا چاہتے ہیں.آپ نے
فرمایا کہ
Page 189
186
جس کو ام ہانی نے پناہ دی میں بھی اس کو پناہ دیتا ہوں.پس چار ہی بدقسمت تھے جو اس
موقع پر قتل کئے گئے اور کسی کو ارتداد کی وجہ سے قتل نہیں کیا گیا.پانچواں ثبوت.اس امر کا پانچواں ثبوت کہ اسلام میں محض ارتداد کیلئے کوئی
شرعی حد مقرر نہیں کی گئی ، خود وہ روایات ہیں جن کو قتل مرتد کی تائید میں پیش کیا جاتا ہے.ان تمام روایات پر جب یکجائی طور پر نظر کی جاتی ہے تو ان سے بھی یہی امر ثابت ہوتا ہے
که محض ارتداد کے لئے آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم نے کسی فرد واحد کو بھی قتل تو الگ رہا کوئی
اور سزا بھی نہیں دی.اب میں ذیل میں ان روایات کو نقل کرتا ہوں.جن کو قتل مرتد کی
حمائت کرنے والے مولوی صاحب نے پیش کیا ہے.( ا ) عن ابي قلابة عن انس قال قدم اناس من عكل او عرينة
فاجتووا المدينة فامرهم النبى صلعم بلقاح وان يشربوا من ابوالها
والبانها فانطلقوا فلما صحوا قتلوا راعى النبي صلى الله عليه وسلم
واستاقوا النَّعَمَ فجاء الخبر فى اوّل النهار فبعث في آثارهم فلما
ارتفع النهار جي بهم فقطع ايديهم وارجلهم وسمرت اعينهم
والقوا في الحرّة.( بخاری.ترندی.کتاب الطہارۃ.مسلم.ابوداؤد.نسائی.کتاب المحاربة - بتقارب الالفاظ )
(۲) حدثنا ابو النعمان محمد بن الفضل حدثنا حماد بن زيد عن
ايوب عن عكرمة قال أُتِىَ عَلِيٌّ بزنادقة فاحرقهم فبلغ ذلك ابن عباس
فقال لوكنت انا لم احرقهم لنهى رسول الله صلى الله عليه
وسلم لا تعذبوا بعذاب الله» ولقتلتهم لقول رسول الله صلى الله
عليه وسلم "من بدل دينه فاقتلوه“.بخاری جلد 4 کتاب استتابة المرتدين)
Page 190
187
(۳) مالك عن زيد بن اسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال من غير دينه فاضربوا عنقه (موطا )
(۴) عن ابن عمران عثمان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه
وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم الا بإحدى ثلاث - رجل زنى بعد
احـصــانــه فـعليه الرّجم اوقتل عمدًا فعليه القود او ارتَدَّ بعد اسلامه
فعلیه القتل“ (نسائی) نسائی کی ایک روایت میں ہے ” کفر بعد اسلامہ“
الله
(۵) عن مسروق عن عبد الله (ابن مسعود) قال قال رسول ا
صلى الله عليه وسلم لا يحل دم رجل مسلم يشهد ان لا اله الا الله
واني رسول الله إِلا بِإِحْدَى ثلاث - القيّب الزاني والنفس بالنفس
والتارك لدينه المفارق للجماعة (ابوداؤد ومسلم.ترمذی.ابن ماجہ )
ایک روایت میں ہے ”و المارق لدينه الفارق للجماعة“
(۲) من خالف دينه دين الاسلام فاضربوا عنقه (طبرانی)
یہ وہ احادیث ہیں جن کو حامیان
قتل مرتد نے پیش کیا ہے.ان میں سے بعض
احادیث دوسرے الفاظ کے ساتھ بھی آتی ہیں مگر چونکہ ان دوسری احادیث سے پیش کردہ
احادیث پر روشنی پڑتی تھی اور ان کے صحیح معنے سمجھنے میں مددملتی تھی اس لئے ان احادیث کا
نقل کرنا خلاف مصلحت سمجھ کر ان کو نظر انداز کر دیا گیا ہے.مگر چونکہ اس بحث میں ان کا
پیش کرنا ضروری ہے اس لئے میں ان کو ذیل میں درج کرتا ہوں.(۱) عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل
دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله وأن محمدًا رسول الله إلا في
إحدى ثلاث رجل زنی بعد احسان فانه يرجم، ورجل خرج محارب
الله ورسوله فانّه يقتل او يصلب او ينفى او يقتل نفسًا فيقتل بها“
(ابوداؤد كتاب الحدود باب الحكم فى من ارتد)
Page 191
188
(۲) عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحلّ دم
امرئ مسلم الا بِإِحدَى ثلث خصال زان محصن يرجم او رجل
قتل رجلا متعمدًا فيقتل او رجل يخرج من الاسلام فيحارب الله
عز وجل ورسوله فيقتل او يصلب اوينفى من الارض.نسائي.كتاب المحاربة باب الصلب)
(۳)حدثني ابو قلابة في حديث طويل) فوالله ماقتل رسول الله
صلى الله عليه وسلم احدًا قط الا في احدى ثلاث خصال - رجل
قتل بجريرة نفسه فقتل او رجل زنی بعد احصان او رجل حارب
الله ورسوله وارتد من الا سلام“.(بخارى كتاب الديات.باب القسامة)
(۴) حدثنی سلمان ابو رجاء مولی ابی قلابة عن أبي قلابة.....فقال عمر بن عبدالعزيز) ما تقول يا عبدالله بن زيد قلت ما
علمت نفسا حل قتلها في الاسلام الا رجل زنى بعد احصان اوقتل
نفسا بغير نفس او حارب الله و رسوله صلى الله عليه وسلم.(صحیح بخاری.كتاب التفسير.باب انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الآية)
جو احادیث او پر نقل کی گئی ہیں ان میں سے ایک فعلی حدیث ہے جس میں ایک
خاص واقعہ کا ذکر ہے.ایک حدیث ایسی ہے جس میں ایک صحابی قسم کھا کر بیان کرتا ہے کہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تین قسم کے لوگوں کو قتل کروایا ہے.اس کے سوا کسی کو
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے قتل نہیں کیا گیا.ایک اور حدیث میں بھی اسی مضمون
کی شہادت ہے.باقی قولی احادیث ہیں.
Page 192
189
اب یہ ایک ثابت شدہ حقیقت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شرعی احکام کو
صرف زبانی طور پر ہی بیان نہیں فرمایا بلکہ شریعت اسلامی کے تمام حدود کو خود عملی طور پر نافذ
بھی کیا.اللہ تعالیٰ نے خود آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایسے حالات پیدا کر
دئے جبکہ ان شرعی احکام اور حدود کے جاری کرنے کی ضرورت پیش آئی.اس طرح آپ
نے نہ صرف شرعی حدود کا زبانی طور پر اعلان کیا بلکہ عملاً ان کو جاری کر کے بھی دکھا دیا.اور
اس طرح دونوں پہلوؤں سے یعنی قولی و عملی طور پر آپ نے شریعت کی تکمیل فرما دی.اب
ہمارے لئے یہ نہایت خوشی کا مقام ہے کہ موجودہ بحث میں مخالفین کی طرف سے صرف قولی
روایات ہی نقل نہیں کی گئیں بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کو بھی اپنے دعوی کی
تائید میں پیش کیا ہے.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ ایک مشہور واقعہ ہے جبکہ
مرتدین کو قتل کرنے کا موقع پیش آیا اور یہی واقعہ ہمارے درمیان اور فریق ثانی کے درمیان
اس بحث کا فیصلہ کر دے گا.مخالفین کا یہ دعوی ہے کہ اسلام میں ارتداد اور تنہا ارتداد کی
شرعی سزا مقرر کی گئی ہے اور ہمارا دعوی ہے کہ ارتداد کی سزا صرف جہنم ہے.محض ارتداد
کے لئے اس دنیا میں شریعت اسلام نے کوئی سزا مقرر نہیں کی.آؤ اب ہم اسی مثال کو
دیکھیں جس کو قتل مرتد کے حامیوں نے اپنے دعوای کی تائید میں پیش کیا ہے.اگر
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عملی مثال سے مخالفین کا دعوی ثابت ہو جائے یعنی
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ان کے اس دعوای کو ثابت کر دے کہ شریعت اسلام میں
محض ارتداد اور تنہا ارتداد کی سزا قتل مقرر کی گئی ہے تو ہم اس غلطی کا اقرار کر لیں گے لیکن اگر
اس مثال سے جس کو انہوں نے خود اپنے دعوی کی تائید میں پیش کیا ہے ہمارے ہی دعوای
کی تائید ہوئی کہ ارتداد اور تنہا ارتداد کے لئے شریعت اسلام میں کوئی سزا مقر رنہیں کی گئی
اور
کبھی کسی مرتد کو قتل کیا گیا تو ارتداد کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کے کسی دوسرے جرم کی وجہ
سے
قتل کیا گیا.تو پھر حامیان قتل مرتد پر واجب اور لازم ہوگا کہ وہ بھی اپنی غلطی کا اقرار
Page 193
190
کریں اور اس بات کا اعلان کریں کہ اسلام میں محض ارتداد کے لئے قتل کی سزا مقرر نہیں کی
گئی ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی ایک بھی ایسا ثابت شدہ واقعہ نہیں
جبکہ کسی مرتد کو محض ارتداد کے لئے قتل کی یا اور کسی قسم کی سزادی گئی ہو بلکہ اگر کسی مرتد کو سزا
دی گئی تو وہ اس کے ارتداد کی وجہ سے نہ تھی بلکہ اس کے دوسرے جرموں کی وجہ سے تھی.جس واقعہ کو قتل مرتد کے دعویداروں نے اپنی حمایت میں پیش کیا ہے وہ صحیح بخاری اور دیگر
کتب حدیث میں موجود ہے اور وہ اس حدیث میں مذکور ہے جو مندرجہ بالا فہرست میں
نمبر (۱) میں دی گئی ہے اس کا ترجمہ حسب ذیل ہے.ابی قلابہ انس سے روایت کرتے ہیں کہ شکل یا عرینہ قبیلے کے کچھ آدمی آئے.مدینہ کی آب و ہوا ان کو موافق نہ آئی.آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا
کہ وہ شیر دار اونٹنیوں میں جا کر رہیں اور ان کا دودھ اور پیشاب پیئیں.وہ اونٹنیوں
میں جا کر رہنے لگے.جب وہ تندرست ہو گئے تو انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کے چرواہے کو قتل کر دیا اور اونٹ ہانک کر لے گئے.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو
دن کے ابتدائی حصہ میں اس واقعہ کی خبر پہنچی.آپ نے ان کے پیچھے آدمی بھیجے اور
جب سورج اونچا ہو گیا ان کو پکڑ کر لے آئے.آپ نے ان کے ہاتھ اور پاؤں کٹوا
دئے اور ان کی آنکھوں میں گرم لوہے کی سلائی پھیری گئی اور ان کو پتھریلی زمین
میں پھینک دیا گیا.“
اب میں ناظرین کے آگے اس حدیث کے الفاظ رکھتا ہوں اور انہی سے انصاف
چاہتا ہوں.وہ اس حدیث کے الفاظ کو پڑھیں اور بتائیں کہ یہاں جن لوگوں کا ذکر ہے کیا
ان سے صرف ارتداد کا جرم سرزد ہوا تھایا انہوں نے کچھ اور بھی کیا تھا ؟ وہ بار بار اس حدیث
کو پڑھیں اور مجھے بتائیں کہ ان کو کیوں سزا دی گئی؟ حدیث ہمیں کیا بتلاتی ہے؟ کیا
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے اس لئے آدمی دوڑائے تھے کہ وہ اسلام سے
Page 194
191
منحرف ہو گئے تھے اور اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ان کو پکڑ کر ارتداد
کی عبرتناک سزادی جائے تا آئندہ کوئی شخص اسلام قبول کرنے کے بعد ارتداد کا خیال نہ
کرے؟ یا اس لئے ان کے پیچھے آدمی بھیجے تھے کہ انہوں نے ایسی شرارت کی کہ اس کوسن
کر بدن پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں.وہ بیمار تھے.آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم نے ان
پر احسان کیا.شیر دار اونٹنیاں دیں کہ وہ ان کا دودھ پیئیں مگر وہ ایسے خبیث باطن اور
بدمعاش تھے کہ انہوں نے اس احسان کا یہ بدلہ دیا کہ جب تندرست ہو گئے تو آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے آدمیوں
کو قتل کر دیا اور اونٹوں کو لے کر بھاگ گئے.میں نہیں سمجھ سکتا
اس سے بدتر کیا شرارت ہو سکتی ہے؟ حیوانوں پر بھی احسان کا اثر ہوتا ہے.بھیٹریوں اور
درندوں پر بھی احسان کرو وہ بھی احسان کا احساس رکھتے ہیں کتے بھی اپنے محسن کے لئے
جان قربان کر دیتے ہیں.جنگل کے درندے اور ہوا کے پرندے بھی احسان کو قدر کی نگاہ
سے دیکھتے ہیں.وہ لوگ جن کا حدیث مذکورہ بالا میں ذکر ہے انسانیت کے تمام احساسات
سے ہی خالی نہ تھے بلکہ درندوں سے بھی بدتر ثابت ہوئے.انہوں نے نہ صرف ایک
انسان
کو قتل کیا اور ڈا کہ مارا بلکہ اپنے حسن کا کھلم کھلا مقابلہ کیا اور حاربوا اللہ ورسولہ کا
اپنے تئیں مصداق ثابت کیا.اس لئے وہ اس قابل تھے کہ ان کو حسب فحوائے آیت کریمہ
إِنَّمَا جَزَوا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَلُوا أَوْ
يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ
لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ -
(المائدة: 34)
یعنی جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور فساد کی غرض سے ملک میں
جنگ کی آگ بھڑ کانے کے لئے دوڑتے پھرتے ہیں ان کی مناسب سزا یہی ہے کہ
ان میں سے ایک ایک کو قتل کیا جائے یا صلیب پر لٹکا کر مارا جائے یا ان کے ہاتھ اور ان
Page 195
192
کے پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دیئے جائیں یا انہیں ملک سے نکال دیا جائے.اگر یہ
سز املتی تو ان کے لئے دنیا میں رسوائی کا موجب ہوتی اور آخرت میں بھی ان کے لئے
بہت بڑا عذاب مقدر ہے.قتل کی سزا ایک عبرتناک رنگ میں دی جاتی.مگر حامیان
قتل مرتد کی رائے ہے کہ
ان کا فعل اس قابل نہ تھا کہ ان کو ایسی سخت سزا دی جاتی.ان کو ایسی عبرتناک سزا دینے کی
وجہ یہ تھی کہ وہ اسلام لا کر پھر مرتد ہو گئے تھے اس وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر
سخت غصہ آیا.واقعات سے صاف ظاہر ہے کہ عسکل کے لوگوں کو یہ سخت سزا اس لئے نہیں دی گئی
تھی کہ انہوں ارتداد اختیار کیا تھا بلکہ اس سختی کی اصل وجہ ان کے جرائم کی وحشیانہ کیفیت
تھی.مگر حامیان قتل مرتد اس سختی کو ان کے ارتداد کی طرف منسوب کر کے آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کو ایک تنگ ظرف اور تنگ خیال ملا کی شکل میں پیش کرتے ہیں کہ آپ
( نعوذ باللہ ) اس بات کو برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی شخص آپ کے مذہب کو ایک دفعہ
قبول کر کے پھر اس کو ترک کر دے.اس وجہ سے آپ کا غضب عکل کے لوگوں کے
خلاف بھڑ کا اور آپ نے سادہ قتل پر اکتفا نہ کیا بلکہ سخت عذاب دے کران کو مارا اور سخت
عذاب دینے کی اصل وجہ ان کا ارتداد ہی تھا.افسوس ہے ان لوگوں پر کہ کس طرح یہ لوگ اپنے نفسانی جذبات کی پیروی کر کے
آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم کو ایک قابل اعتراض پیرایہ میں پیش کرنے سے باز نہیں
آتے.جس وحشیانہ رنگ میں شکل کے لوگوں نے ان جرائم کا ارتکاب کیا وہ ہر ایک
انصاف پسند انسان کے نزدیک ان کو اس عبرتناک سزا کا مستحق بنانے کے لئے کافی سے
بھی زیادہ ہے اور اس امر کی ہر گز ضرورت نہیں کہ ان کی سختی کو ان کے ارتداد کی طرف
منسوب کیا جائے.لیکن اگر حامیان قتل مرتد کو اس سے تسلی نہیں ہوتی تو میں عکل کے
Page 196
193
لوگوں کے متعلق کچھ مزید جواب ذیل میں درج کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ ان حوالجات
کے بعد لوگوں
کو تشفی ہو جائے گی.(۱) ابو داؤد میں آیا ہے کہ انہوں نے صرف ایک چرواہے کو قتل نہیں کیا تھا بلکہ وہ
چر وا ہے کئی تھے جنہیں
قتل کیا گیا.(۲) مسلم ، ترندمی ،نسائی اور دار قطنی میں حضرت انسؓ کی روایت ہے.انما سمل النبي صلى الله عليه و سلم أعين اوليك لانهم سملوا أعين الرعاة.یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی آنکھوں میں اس لئے گرم لوہے کی
سلائی پھر وائی تھی کہ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہوں سے یہی سلوک کیا
تھا اور ان کی آنکھوں میں گرم لوہے کی سلائیاں پھیری تھیں.(۳) ابوداؤد کے حاشیہ پر بحوالہ لمعات لکھا ہے.انما فعل صلعم قصاصًا لانهم كذالك فعلوا بالرعاة فانه قد روى
انهم سملوا اعين الرعاة وقطعوا ايديهم وارجلهم وغرزوا الشوك
في ألسنتهم وأعينهم حتى ماتوا.یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ان سے سلوک کیا وہ قصاص کے طور پر کیا
کیونکہ یہ روایت کیا گیا ہے کہ انہوں نے چرواہوں کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیری
تھیں، ان کے ہاتھوں اور پاؤں کو کاٹا تھا اور ان کی زبانوں اور آنکھوں میں کانٹے گاڑے
تھے یہاں تک کہ وہ اس عذاب کو سہتے سہتے مر گئے.(۴) روح المعانی جلد ۲ صفحہ ۱۴۸ پر لکھا ہے."وقيل هم العرنيون الذين اغار وا على السرح واخذوا يسارا راعى
رسول الله صلى الله عليه وسلم ومثلوا به فقطعوا يديه ورجليه
و غرزوا الشوك فى لسانه وعينيه حتى مات.
Page 197
194
کہا گیا ہے کہ وہ عربی لوگ تھے جنہوں نے چرنے والے اونٹوں پر ڈاکہ مارا.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے لیسار کو پکڑا اور قتل کرنے سے پہلے اس کا مثلہ
کیا.اس کے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کاٹ ڈالے اور اس کی زبان میں اور اس کی
دونوں آنکھوں میں کانٹے گاڑے یہاں تک کہ وہ اس تکلیف کی وجہ سے مرگیا.ان روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان لوگوں سے چار فعل سرزد ہوئے.(۱) قطع امید کی.(۲) قطع رجل.(۳) سمل امین.(۴) غرز الشوک.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا
دیتے وقت تین سزائیں دیں یعنی ہاتھوں کا کاٹنا.پاؤں کا کاٹنا.آنکھوں میں سلائی
پھیرنا.ان کے چوتھے فعل کی سزا نہیں دی گئی یعنی ان کی زبانوں میں کانٹے نہیں گاڑے
گئے.تعجب ہے کہ حامیان
قتل مرتد کھڑے تو اس لئے ہوئے تھے کہ ثابت کریں کہ اسلام
میں محض ارتداد کی سزا قتل ہے لیکن ثبوت میں ایسے لوگوں کی مثال پیش کی جنہوں نے ایک
جرم کا نہیں بلکہ کئی جرموں کا ارتکاب کیا اور ارتکاب بھی نہایت ہی وحشیانہ طور پر کسی
روایت میں یہ درج نہیں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ ان کو ارتداد کی
وجہ سے سزا دی جاتی ہے.نہ حضرت انس جو اس واقعہ کے راوی ہیں بیان کرتے ہیں کہ ان
کو ارتداد کی وجہ سے سزا دی گئی یا اس سزا میں ان کے ارتداد کا کچھ دخل تھا.بلکہ روایت
سے ظاہر ہے کہ ان کو ان کے وحشیانہ جرائم کی سزا دی گئی.تاریخ واقعہ سے تو ہمارا دعوای
ثابت ہوتا ہے نہ کہ حامیان
قبل مرند کا.ہمارا دعوی یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
کسی فرد کو بھی محض ارتداد کی وجہ سے کوئی سزا نہیں دی.اگر دی ہے تو ارتداد کی وجہ سے نہیں
بلکہ دیگر وجوہات سے.اور جو واقعہ ہمارے سامنے پیش کیا گیا ہے اس سے ہمارے ہی
دعوی کی تائید ہوتی ہے نہ کہ حامیان قتل مرتد کی.کیونکہ یہاں جن لوگوں
کو قتل کیا گیا ان
کے وہ جرائم صراحت کے ساتھ مذکور ہیں جن کی وجہ سے ان کو سزا دی گئی.پس یہ واقعہ
ہماری تائید میں ہے نہ حامیان قتل مرتد کی تائید میں.
Page 198
195
دوسرا تاریخی واقعہ جو قتل مرتد کی تائید میں پیش کیا جاتا ہے وہ ابن خطل کا
واقعہ ہے جس کو فتح مکہ کے موقع پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے قتل کیا گیا.افسوس کہ صرف مرتد کا لفظ دیکھ لیا جاتا ہے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ آیا وہ صرف ارتداد کا
ہی مرتکب ہوا تھا یا کوئی اور جرم بھی اس سے سرزد ہوا تھا.اسی ابن خطل کی نسبت
مواہب اللہ نیہ میں لکھا ہے.وانما امر بقتل ابن خطل لانه كان مسلما فبعثه صلى الله عليه
وسلم مصدقا وبعث معه رجل من الانصار و كان معه مولی یخدمه و
كان مسلما فنزل منزلا فامر المولى ان يذبح تيسا ويضع له طعاما
ونام فاستيقظ ولم يصنع له شَيْئًا فعدا عليه فقتله ثم ارتد مشركًا
"
وكانت له فتيتان تغنيان بهجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن خطل کے قتل کرنے کا حکم دیا کیونکہ وہ مسلمان
تھا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو زکوۃ جمع کرنے کے لئے بھیجا اور اس کے ساتھ
ایک انصاری کو بھی بھیجا گیا اور اس کے ساتھ ایک آزادشدہ غلام تھا جو اس کی خدمت کرتا
تھا اور وہ مسلمان تھا.وہ ایک منزل پر اُترا اور غلام کو حکم دیا کہ ایک بکرا ذبح کرے اور اس
کے لئے کھانا تیار کرے.یہ کہہ کر سو گیا.جب جا گا تو ابھی تک غلام نے کوئی کام نہیں کیا تھا
پس اس نے اس پر حملہ کیا اور اس
کو قتل کردیا اور پھر مرتد ہوکر مشرک ہو گیا.اور اس کے پاس
دو لونڈیاں تھیں وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو کے شعر گایا کرتی تھیں.یہ ہیں حالات
ابن خطل کے.اب مولوی صاحبان خود ہی فرماویں کہ کیا اس کے واقعہ سے ثابت ہوتا ہے
کہ اسلام میں محض ارتداد کی سزا قتل ہے؟ اس واقعہ نے تو ہمارے ہی دعوی کی تصدیق کی
ہے کہ اسلام میں محض ارتداد کی سزا قتل نہیں ہے اور یہ کہ اگر کسی مرتد کو قتل کیا گیا تو اسے
ارتداد کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کے دوسرے جرموں کی وجہ سے.
Page 199
196
تیسرا تاریخی واقعہ جس کو قتل مرتد کی تائید میں پیش کیا جاتا ہے وہ مقیس بن
صبابہ کا واقعہ ہے جس کو فتح مکہ کے موقع پر قتل کیا گیا اس کی نسبت زرقانی مواہب اللہ نیہ کی
شرح میں لکھتا ہے.كان أسلم ثم اتى على انصارى فقتله وكان الأنصارى قتل اخاه
هشاماخطأ في غزوة ذى قرد ظنّه من العدوّ فجاء مقيس فأخذ الديّة
ثم قتل الانصاري ثم ارتد ورجع إلى قريش.یہ مسلمان ہوا پھر جا کر ایک انصاری
کو قتل کر دیا اس انصاری نے غلطی سے اس کے
بھائی ہشام کو غزوہ ذی قرد میں دشمن سمجھ کر قتل کر دیا تھا.مقیس نے پہلے دیت لے لی اس
کے بعد اس کو قتل کر دیا پھر مرتد ہو کر قریش کے ساتھ جا کر شامل ہو گیا.اب حامیان قتل
مرتد خود ہی انصاف کے ساتھ فیصلہ فرما دیں کہ اگر بالفرض یہ شخص مرتد نہ ہوتا تو کیا اس کو
چھوڑ دیا جاتا؟ کیا اس کا جرم اس قابل نہ تھا کہ اس
کو قتل کی سزادی جاتی؟ ایک صحابی نے
غلطی سے اس کے بھائی کو ایک لڑائی میں دشمن سمجھ کر قتل کر دیا اور اس کا خون بہا ادا کر دیا مگر
اس نے دیت لینے کے بعد پھر اس صحابی کو قتل کر دیا جیسا کہ زمانہ ھذا میں ریاست کابل
نے پہلے اپنے مقتول سپاہی کے عوض میں سلطنت انکی سے دیت لے لی پھر دیت لینے کے
بعد سلطنت اٹلی کے آدمی کو قتل بھی کر دیا چنا نچہ اپنے اس فعل کی پاداش ان کو بھگتنی پڑی.غرض مقیس بن صبابہ کے واقعہ سے ہرگز ثابت نہیں ہوتا کہ اسلام میں محض ارتداد کی سزا قتل
ہے بلکہ اس سے ہمارے ہی دعوای کی تائید ہوتی ہے کہ اسلام میں محض ارتداد کے لئے کوئی
سزا مقر نہیں کی گئی اور جن مرتدین کو قتل کیا گیا ان کو ارتداد کی سزا میں
قتل نہیں کیا گیا بلکہ ان
کے دیگر جرائم کی وجہ سے ان کو قتل کی سزا دی گئی.عسکل یا عرینہ کے لوگوں اور ابن خطل اور
مقیس ابن صبابہ کے واقعات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے ارتداد کی وجہ ان کے
اپنے جرائم تھے.وہ ایسے جرائم کے مرتکب ہوئے جن کی یقینی سزا قتل تھی اس لئے ان جرائم
Page 200
197
کے ارتکاب کے بعد وہ دشمنوں سے جاملے.یہی ان کا ارتداد تھا انہوں نے مسلمانوں کو قتل
کیا اور اس کے بعد مسلمانوں کے دشمنوں میں جا کر شامل ہو گئے یا شامل ہونے کی کوشش
کی.ان کے اس فعل کا نام مؤرخین نے ارتداد رکھا ہے اور صاف ظاہر ہے کہ اگر ارتداد
اسی چیز کا نام ہے تو ہمیں اس امر سے ذرا بھی اختلاف نہیں کہ ایسے مرتد کی سزا بے شک
قتل ہے.ایک شخص پہلے مسلمانوں کے لشکر میں شامل ہے وہاں
قتل کا جرم کر کے وہ دشمن
کے لشکر کی طرف بھاگتا ہے اور آئندہ وہ ہر موقع پر مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے اور
موقع پا کر مسلمانوں کو قتل کرنے کے لئے تیار ہے اور مسلمانوں کا کھلم کھلا دشمن ہے ایسا
مرتد بے شک قابل ہے کہ اس کو قتل کیا جاوے لیکن اگر یہ کہا جاوے کہ ایک شخص شیطانی
وسوسوں کا شکار ہو کر اسلام سے منحرف ہوتا ہے اور کوئی اور دین اپنے لئے اختیار کرتا ہے مگر
اختلاف رائے سے بڑھ کر اس کو اسلام کے ساتھ کوئی مخالفت نہیں ایسے مرتد کی سزا بھی
اسلام میں قتل مقرر کی گئی ہے تو ہم ایسے عقیدہ کی بڑے زور کے ساتھ مخالفت کریں گے
کیونکہ یہ عقیدہ سراسر باطل اور جھوٹ ہے اور اسلام کے پاک دین کو بدنام کرنے والا ہے
اور ہم ڈنکے کی چوٹ کے ساتھ اعلان کرتے ہیں کہ کوئی شخص یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ
آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم نے محض ارتداد اور تنہا ارتداد کے لئے کسی کو قتل کی سزا دی ہو.اس باطل عقیدہ کے حامی بے شک ایڑیوں تک زور لگا لیں وہ اسلامی تاریخ سے ایک بھی
ایسا ثابت شدہ واقعہ پیش نہیں کر سکتے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو محض اس
لئے قتل کی سزا دی کہ وہ شیطانی وسوسوں کا شکار ہو کر اسلام سے مرتد ہو گیا اور اختلاف
رائے سے بڑھ کر اس کو اسلام کے ساتھ کوئی مخالفت نہیں تھی.حامیان قتل مرتد اپنے تمام
اعوان وا کا بر کے ساتھ مل کر جس قدر چاہیں تاریخ اسلام کے اوراق کی ورق گردانی کریں
ان کو ایک بھی ایسی مثال نہیں ملے گی جس سے یہ امر قطعی اور حتمی طور پر پایہ ثبوت تک پہنچ
جائے کہ آپ نے کبھی کسی ایسے شخص کو قتل کرایا جس سے سادہ ارتداد کے سوا اور کوئی شرنہ سرزد
Page 201
198
ہوا اور نہ اس سے متوقع تھا.اس تلاش میں ان کو ایسی مثالیں تو ضرور ملیں گی جب کہ آپ
نے مرتدین کو ان کے حال پر چھوڑ دیا اور ان سے کسی قسم کا تعارض نہ کیا.اور ایسے مرتدین
کی مثالیں بھی ان
کو ملیں گی جبکہ آپ نے بعض مرتدین کو قتل کرایا مگر نہ ان کے ارتداد کی وجہ
سے بلکہ ان کے دوسرے جرائم کی وجہ سے لیکن ان کو ایک بھی ایسی مثال نہ ملے گی جس سے
یقینی طور پر یہ ثابت ہو کہ آپ نے کسی ایک فرد واحد کو بھی اس لئے قتل کی سزادی ہو کہ اس
نے محض ارتداد کا ارتکاب کیا اور اس کے وجود سے اور کسی قسم کا خطرہ اسلام کو اور مسلمانوں
کو نہیں تھا.یہ میری طرف سے ایک چیلنج ہے اگر حامیان قتل مرتد میں طاقت ہے تو اٹھیں اور
میرے اس چیلنج کو قبول کریں.اور اگر وہ ایسا نہیں کر سکتے تو پھر وہ کیوں اپنے خیالات
باطلہ کی بناء پر اسلام جیسے پاکیزہ دین اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مبارک وجود کو
بد نام کر رہے ہیں.جیسا کہ اوپر ذکر ہو چکا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے وقت گیارہ
بارہ آدمیوں کے قتل کا حکم دیا جن میں سے تین مرتد تھے لیکن ان کے قتل کے حکم کی یہ وجہ نہ تھی
کہ وہ مرتد تھے بلکہ اس حکم کی وجہ ان کی دوسری شرارتیں تھیں.ان مرتدین اور ایک چوتھے
شخص حویرث کے قتل کے حکم کا ذکر کرتے ہوئے زرقانی لکھتا ہے.خصهم بالذكر لشدّة ما وقع منهم اذى الاسلام واهله
(صفحہ 321 جلد 2)
یعنی (جیسا کہ ایک روایت میں ہے ) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چار
شخصوں کا خصوصیت سے اس لئے ذکر فرمایا کہ ان کی طرف سے اسلام کو اور مسلمانوں کو
سخت تکلیف پہنچی تھی.پس معلوم ہوا کہ جب دوسروں کے ساتھ ان تین مرتدین کے قتل کا
حکم دیا گیا تو اس کی وجہ ان
کا ارتداد نہ تھا بلکہ اس حکم کی یہ وجہ تھی کہ ان کی طرف سے اسلام کو
اور مسلمانوں کو خصوصیت کے ساتھ بہت تکلیف اور دکھ پہنچ چکا تھا.
Page 202
199
ممکن ہے کہ کسی کو یہ وہم ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی سرح کو
اس لئے معاف کیا کہ وہ تائب ہو کر دوبارہ اسلام میں داخل ہونا چاہتا تھا.مگر یہ عذر بالکل
غلط ہے کیونکہ اول تو آپ نے ان تینوں میں سے کسی کو یہ موقع ہی نہیں دیا کہ وہ تائب ہوکر
اپنی جان بچالے.اگر آپ ایسا موقع دیتے تو یقینا تینوں بڑی خوشی سے ایسے موقع سے فائدہ
اٹھاتے.پس آپ کا ان کے متعلق قطعی حکم نافذ کرنا استنا بہ کی طرف رجوع نہ کرنا ظاہر کرتا
ہے کہ ارتداد ان کا جرم نہ تھا بلکہ جیسا کہ زرقانی نے لکھا ہے ان کا جرم یہ تھا کہ ان تینوں نے
بھی اسلام کو اور اہل اسلام کو اسی طرح تکلیف اور دکھ دیا تھا جیسا کہ حویرث نے جس کو آپ
نے ان کے ساتھ شامل کیا.دوسری اگر آپ نے اس کی تو بہ کی وجہ سے معاف کیا تھا تو پھر
آپ معافی دینے سے پہلے بہت دیر تک کیوں خاموش رہے؟ اور آپ کیوں اس امر کا
انتظار فرماتے رہے کہ آپ کے صحابہ میں سے کوئی شخص اٹھے اور اس کا سر تلوار سے کاٹ
دے؟ آپ کو چاہئیے تھا کہ فوراً اس کو معاف کر دیتے.اور اگر کوئی صحابی اس کو قتل کرنے
کیلئے اٹھتا تو اس پر سخت ناراض ہوتے (جیسا کہ ایسے موقعوں پر آپ ہمیشہ قتل کرنے
والوں پر سخت ناراضگی کا اظہار فرماتے) نہ یہ کہ خود انتظار فرماتے کہ کوئی صحابی اس کو قتل کر
دے.آپ نے قتل کا حکم صرف ارتداد کی وجہ سے دیا تھا اور اُس سے اور کوئی شرظاہر نہیں
ہوئی تھی تو پھر تو چاہئے تھا کہ آپ اُس کے تائب ہونے پر فوراً اُس کو معاف کر دیتے اور اگر
کوئی صحابی اسے قتل کرنا چاہتا بھی تو اُس پر سخت ناراض ہوتے نہ یہ کہ آپ بہت دیر تک
خاموش رہتے اور اس امر کی انتظار میں رہتے کہ کوئی صحابی اُٹھے اور اسے قتل کر دے.اگر عبداللہ بن ابی سرح اور اُس کے ساتھیوں سے صرف ارتداد کا ہی ظہور ہوا تھا اور
یوں وہ بالکل بے قصور تھے تو پھر تو چاہئیے تھا کہ حسب قول حامیان قتل مرتد آنحضرت صلے اللہ
علیہ وسلم صحابہ کو یہ حکم دیتے کہ ان
کو تو بہ کیلئے ترغیب دی جائے اور اسلام کی خوبیوں کی ان کو
تلقین کی جائے اور ان
کو بتایا جائے کہ اگر تم دوبارہ اسلام میں داخل نہیں ہو گے تو تمہیں قتل کیا
Page 203
200
جائے گا.لیکن ایسا نہیں کیا گیا بلکہ بغیر کسی شرط کے اُن کے متعلق قتل کا حکم جاری کیا گیا.پس
معلوم ہوا کہ ان کا جرم جس کی وجہ سے اُن کے متعلق ایسا حکم نافذ کیا گیا ارتداد نہ تھا بلکہ وہ
اپنے دوسرے افعال اور رویہ کی وجہ سے مستوجب قتل ہو چکے تھے.اور عبداللہ بن ابی سرح
کو اس لئے معاف نہیں کیا گیا کہ وہ تائب ہو کر آیا تھا بلکہ اس لئے کہ حضرت عثمان نے اُس
کو پناہ دی تھی اور اُس کے لئے آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم سے معافی کی درخواست کی
تھی.جیسا کہ لکھا ہے.فاستجار له عثمان بن عفان رضی الله عنه فاجاره النبی صلی الله
عليه وسلم.(روح المعانی جلد 4 صفحہ 484)
عبداللہ بن ابی سرح کی ایک شرارت کا روایات کی رو سے قرآن شریف میں بھی
ذکر ہے.کیونکہ آیت سـانـزل مثل ما انزل اللہ کا شان نزول یہی عبداللہ بن ابی سرح
بتایا گیا ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا جاری رکھتا تھا اور اسلام
اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت اور حقارت کو ملک میں پھیلا تا تھا اور اسلامی
حکومت کے خلاف ایجی ٹیشن کرتا تھا.حامیان
قتل مرتد اس بات سے تو عاجز آگئے ہیں کہ کوئی ثابت شدہ تاریخی واقعہ ایسا
پیش کریں جس سے یہ ظاہر ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے محض ارتداد کی وجہ سے کسی کو
قتل کروایا.مگر مرتا کیا نہ کرتا.ڈوبنے والا انسان ایک تنکہ پر بھی ہاتھ مارتا ہے کہ شائد اسی
کے سہارے سے وہ غرق ہونے سے بچ جائے.چنانچہ موجودہ صورت میں بھی حامیان قتل مرتد
نے بھی ایسا ہی اضطراب دکھایا ہے اور اپنے دعوئی کو ثابت کرنے کیلئے جو چیز بھی سامنے آئی
ہے اُس پر ہاتھ مارا ہے اور یہ نہیں دیکھا کہ وہ اس قابل ہے بھی یا نہیں کہ ان کے لئے کسی
سہارے کا موجب ہو سکے.کسی مرد کے متعلق تو ان کو ضعیف سے ضعیف روایت بھی نہیں ملی
جس میں یہ بیان کیا گیا ہو کہ محض ارتداد کے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس کو قتل کی
Page 204
201
سزادی.ایک دو نا قابل اعتبار روایات کسی بے نام ونشان عورت کے متعلق حامیان قتل کو
کہیں سے مل گئی ہیں اور انہی کو غنیمت سمجھا ہے اور بغیر چھان بین کے صرف رعب ڈالنے
کے لئے ان کو پیش کر دیا ہے.وہ روایات یہ ہیں.اوّل: عن جابر قال ارتدت امرءة عن الاسلام فأمر النبي صلعم ان
يعرضوا عليها الاسلام فان اسلمت والا قتلت فعرض عليها
الاسلام فأبت ان تسلم فقتلت.دوم: عن عائشة قالت ارتدت امرأة يوم احد فأمر النبي صلعم ان
تُستاب فان عادت والا قتلت.ان روایات کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ یہ دونوں روایات ضعیف الاسناد ہیں.لان في حديث جابر عبدالله بن اذينه جرحه ابن حبّان وقال لايجوز
الاحتجاج به بحال و قال الدار قطنى فى المؤتلف والمختلف متروك.رواه ابن عدي في كامله وقال عبدالله بن اذينه منكر الحديث
( حاشیہ ھدایہ صفحہ 354 ) - مطبع نولکشور محتشی بحاشیہ مولوی محمد حسن سنبلی )
وفي حديث عائشة محمد بن عبد الملك الانصاري قال عبدالله
بن احمد عن ابيه انى قد رأيت هذا وكان اعلى يضع الحديث
ويكذب وقال البخارى منكر الحديث وقال النسائي متروك.(حاشیہ ھدایہ جلد 2 صفحہ 355 )
یعنی پہلی حدیث کے راویوں کے سلسلہ میں عبداللہ بن اذینہ ہے جس پر ابن حبان
نے جرح کی ہے اور کہا ہے کہ کسی صورت میں بھی جائز نہیں کہ ایسی حدیث کو دلیل کے طور
پر پیش کیا جائے جس کے راویوں کے سلسلہ میں عبداللہ بن از بینہ ہو اور دارقطنی نے اس کو
الموتلف اور المختلف میں عبداللہ بن اذینہ کی نسبت لکھا ہے کہ وہ متروک ہے.ابن عدی نے
Page 205
202
اپنی کتاب کامل میں اس حدیث کو نقل کر کے لکھا ہے عبداللہ بن اذینہ منکر الحدیث ہے اور جو
حدیث حضرت عائشہ کی طرف منسوب کر کے بیان کی گئی ہے اُس کے راویوں کے سلسلہ
میں محمد بن عبد الملک انصاری ہے اور اس کے متعلق عبداللہ بن احمد نے اپنے باپ سے
روایت کیا ہے کہ اُس نے کہا کہ میں نے اس شخص کو دیکھا کہ وہ اندھا تھا اور حدیثیں خود
گڑھا کرتا تھا اور جھوٹ بولا کرتا تھا اور بخاری نے اس کو منکر الحدیث قرار دیا ہے اور نسائی
نے اس کو متروک کہا ہے.( حاشیہ ہدایہ جلد 2 صفحہ 355 )
اب یہ حال ہے ان روایات کا جن کو قرآن شریف کی تعلیم کو رڈ کرنے کے لئے
پیش کیا جاتا ہے.ایسی روایات کا پیش کرنا ہی ظاہر کرتا ہے کہ ان لوگوں کے ہاتھ میں کوئی
مضبوط چیز نہیں.اس لئے ایسے چھوٹے ہتھیاروں پر اُتر آئے ہیں.اس کے مقابل میں بخاری کی حدیث کو دیکھو جس میں ایک صحابی قسم کھا کر کہتا ہے
کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے (۱) محارب (۲) زانی محصن (۳) قاتل نفس کے سوا
کسی شخص کو قل نہیں کروایا.یہ حدیث میں اوپر نقل کر چکا ہوں.پھر تعلیق المغنی شرح دار قطنی
صفحہ 339 میں لکھا ہے
ونقل ابن طلاع في الأحكام أنَّه لم ينقل عن النبي صلعم انه قتل
مرتدة.یعنی ابن طلاع نے احکام میں لکھا ہے کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت یہ
مروی نہیں کہ آپ نے کبھی کسی مرتد عورت
کو قتل کروایا ہو اور جن مردوں کی نسبت ایسا بیان
کیا گیا ہے اُن کی نسبت میں ثابت کر چکا ہوں کہ ان کو امداد کے لئے نہیں بلکہ اُن کے
دوسرے جرموں کی وجہ سے قتل کیا گیا.یہاں یہ بیان کر دینا بھی خالی از فائدہ نہ ہوگا کہ جابر کی ایک روایت میں اُس مرتد
کا نام بھی بیان کیا گیا ہے کہ اُس کا نام ام مروان تھا.اور اس اتم مروان کی نسبت مبسوط
Page 206
203
جلد 10 صفحہ 110 میں لکھا ہے.فان أم مروان كانت تقاتل وتحرض على القتال وكانت مطاعة فيهم.یعنی اتم مروان مسلمانوں کے ساتھ جنگ کیا کرتی تھی اور دوسرے لوگوں کو جنگ
کے لئے اکسایا کرتی تھی اور وہ اپنی قوم کی لیڈر تھی.پس اگر ہم مان بھی لیں کہ اتم مروان کو
قتل کیا گیا تو اُس کو ارتداد کیلئے قتل نہیں کیا گیا بلکہ اس لئے کہ وہ محاربت تھی.اب ناظرین نے دیکھ لیا کہ قتل مرتد کے حامی تاریخ اسلام سے ایک واقعہ بھی ایسا
پیش نہیں کر سکتے جس میں یہ ثابت ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مرتد مرد یا مرتدہ
عورت کو محض ارتداد کے لئے قتل کیا ہو.بلکہ اگر کسی مرتد یا مرتدہ کو قتل کیا ہے تو اُس کو ارتداد کی
وجہ سے قتل نہیں کیا بلکہ اس لئے قتل کیا کہ وہ محارب تھے.غرض اس میدان سے تو قتل مرتد
کے حامی خائب و خاسر لوٹتے ہیں اور فتح کا جھنڈا ہمارے ہاتھ میں ہے.اب ہم دوسرے
میدان میں اُترتے ہیں یعنی قولی حدیث کی طرف رجوع کرتے ہیں اور خدا تعالیٰ سے دعا
کرتے ہیں کہ اس میدان میں بھی وہ ہماری اسی طرح ( بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ) یاوری
فرمادے جس طرح کہ اس وقت تک وہ اپنے فضل ورحم سے ہماری دستگیری فرما تا رہا ہے.قولی احادیث کے متعلق یہ بات نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ ہماے مخالفوں نے
اس مضمون کی تمام احادیث کو یکجائی طور پر نہیں لیا بلکہ صرف ایک حصہ نقل کیا ہے اور دوسرا
حصہ نظر انداز کر دیا ہے اور اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ دوسری احادیث اُن کی نظر سے مخفی
تھیں.بلکہ اس لئے کہ اُن کے نقل کرنے سے حقیقت منکشف ہو جاتی تھی اور حقیقت کا
انکشاف اُن کا تمام تانا بانا درہم برہم کر دیتا تھا.اس لئے انہوں نے یہی مناسب سمجھا کہ
تصویر کا ایک رُخ ناظرین کو دکھائیں اور دوسرا رُخ اُن کی آنکھوں سے اوجھل کر دیں تا کہ
وہ تصویر کا صحیح نقشہ اپنی آنکھوں کے سامنے نہ لاسکیں.قتل مرتد کے متعلق قولی احادیث کو میں اوپر بیان کر چکا ہوں.ان تمام احادیث
Page 207
204
میں جو جوالفاظ راویوں نے استعمال کئے ہیں اُن کی فہرست میں ذیل میں درج کرتا ہوں
تا ناظرین اُس ساری فہرست پر یکجائی نظر ڈال کر خود ہی فیصلہ فرما لیں کہ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے کیسے مرتدین کے متعلق قتل کا حکم دیا.وہ فہرست یہ ہے.( ا ) من بدل دينه.(۲) من خالف دينه دين الاسلام (۳) من غير دينه
(۴) ارتد عن الاسلام (۵) كفر بعد الاسلام (٦) المارق لدينه الفارق
للجماعة (۷) رجل خرج محاربًا لِله ورسوله (۸) رجل يخرج من
الاسلام فيحارب الله عز وجل ورسوله (۹) رجل حارب الله
ورسوله و ارتد عن الاسلام (۱) حارب الله ورسوله صلى الله
عليه وسلم (١١) التارك لدينه المفارق للجماعة.مندرجہ بالا فہرست میں بعض احادیث میں تو صرف کفر بعد اسلام یا تبدیلی اسلام یا
تبدیلی دین یا ارتداد کا لفظ بیان کیا گیا ہے اور بعض میں ان الفاظ کے ساتھ مزید شرط
بڑھائی گئی ہے.کسی حدیث میں الفارق للجماعة کے الفاظ بڑھائے ہیں.کسی میں
حارب اللہ ورسولہ کے الفاظ بڑھائے ہیں.کسی میں صرف حارب الله و رسوله
کے الفاظ ہیں اور یہ صیح بخاری کی حدیث ہے.کسی میں خالف دین الاسلام کے الفاظ
ہیں.مگر جب ہم حامیان قتل مرتد کی پیش کردہ فہرست پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا
ہے کہ انہوں نے نہایت احتیاط سے ان احادیث کو نظر انداز کر دیا ہے جن میں محاربہ کا ذکر ہے
حالانکہ یہ احادیث صحیح بخاری میں موجود ہیں اور اُن کی نظر سے مخفی نہیں تھیں.اُن کا ان احادیث
کو قطعاً نظر انداز کر دینا صاف ظاہر کرتا ہے کہ اُنہوں نے اس بحث میں دیانتداری سے کام نہیں
لیا.بلکہ ان احادیث کو اپنے مطلب کے مخالف ہونے کی وجہ سے ترک کر دیا ہے.حامیان قتل مرتد کی اس دیانتداری کی طرف اشارہ کرنے کے بعد میں اب ان
احادیث کی طرف رجوع کرتا ہوں اور ناظرین کی خدمت میں التماس کرتا ہوں کہ ان سب پر
Page 208
205
یکجائی نظر ڈالیں اور دیکھیں کہ ان سے کیا نتیجہ نکلتا ہے.اگر ان سب احادیث میں صرف کفر
بعد اسلام یا تبدیلی کدین یا ارتداد کا ہی ذکر ہوتا اور کسی صحیح حدیث میں کوئی شرط نہ ہوتی مثلاً
الفارق للجماعة کے الفاظ يا خالف دين الاسلام يا خرج محاربا الله
ورسوله يا يخـرج مـن الاســلام فيحارب الله عزّوجل ورسوله يا
حارب الله ورسوله.اور حالات بھی اس قسم کے ہوتے کہ اُس زمانہ میں ایک شخص کا ارتدادصرف تبدیلی دین
تک ہی محدود ہوتا اور اُس کے وجود سے اور کسی قسم کا خطرہ متوقع نہ ہو سکتا تب ہم اس بات
لو تسلیم کر لیتے کہ بے شک ان احادیث سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ محض ارتداد کی سزا قتل ہے
اور پھر اس حالت میں قرآن شریف کی کھلی کھلی تعلیم کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ دیکھتے کہ آیا قتل
کا کوئی ایسا مفہوم ہوسکتا ہے جو قرآن شریف کی تعلیم کے مخالف نہ ہو.مگر یہاں تو صورت
ہی دگرگوں ہے.اگر بعض احادیث میں محض ارتداد کا ذکر ہے تو اُس کے ساتھ دوسری
احادیث میں جو صحیح بخاری اور دوسری کتب صحاح میں موجود ہیں اور اُن میں ارتداد کے
ساتھ محاربہ کی شرط موجود ہے.کسی میں الفارق للجماعة يا المفارق للجماعة کے
الفاظ ہیں.کسی میں خالف دین الاسلام کے الفاظ ہیں.کسی میں صرف حارب الله و
رسولہ کے ہی الفاظ ہیں.اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر ایک امر کے متعلق دو قسم کی
روایات ہوں بعض روایات میں قید ہو اور بعض میں قید کا ذکر نہ ہو تو ایسی صورت میں ہمیں
کیا کرنا چاہئیے.اس کے فیصلہ کے لئے میں خود اپنی طرف سے کوئی قاعدہ پیش نہیں کرتا
بلکہ وہی قائدہ پیش کرتا ہوں جو علماء اسلام میں مسلم چلا آتا ہے.اس امر کے فیصلہ کے لئے
اصول فقہ کا ایک مسلم قاعدہ ہے جو میں ذیل میں نقل کرتا ہوں.نورالانوار میں لکھا ہے.وعندنا لا يحمل المطلق على المقيد وان كانا في حادثة واحدة
لامكان العمل بهما الا ان يكونا فى حكم واحد مثل صوم في قوله
Page 209
206
تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام فان قراءة العامة مطلقة و قراءة
ابن مسعود رضى الله عنه فصيام ثلاثة ايام متتابعات مقيدة بالتتابع
والقراءتان بمنزلة الأيتان في حق المعاملة فيجب ههنا ان تقيد قراءة
العامة ايضا بالتتابع لان الحكم وهو الصوم لا يقبل وصفين متضادين
فاذا ثبت تقيده بطل اطلاقه.(نورالانوار شرح المنار تحت كشف الاسرار شرح المصنف على المنار في الاصول جلد اصفحہ 378 مطبوعہ مصر )
ترجمہ: یہ کہ ہمارے نزدیک مطلق کو مقید پرمحمول نہیں کیا جاتا اگر چہ حادثہ ایک ہو.لیکن
اگر حکم ایک ہو جیسا کہ قرآن کریم میں کفارہ یمین کے تین روزوں کا ذکر آیا کہ اس میں
عام قراءت مطلق ہے جس کے ساتھ کوئی قید نہیں لگی ہوئی کہ وہ روزے یکے بعد
دیگرے مسلسل ہوں.یا کہ درمیان میں وقفہ بھی آجانا جائز ہے.مگر حضرت عبداللہ بن
مسعود کی قراءت میں یکے بعد دیگرے مسلسل بغیر وقفہ کے ان روزوں کے رکھنے کا ذکر
آیا ہے اس واسطے عام قراءت کو اس دوسری قراءت کے ساتھ جو حضرت عبداللہ بن
مسعودؓ کی ہے مقید کرنا ضروری سمجھا گیا ہے.کیونکہ روزہ رکھنے کا یہ حکم ان دو متضاد
صفتوں کے ساتھ متصف نہیں ہو سکتا کہ وہی تین روزے پے در پئے بلا وقفہ بھی رکھے
جائیں اور وقفہ کرنا بھی اس میں جائز ہو.اب حامیان قتل مرتد اس مسلمہ اصول کو ان روایات پر چسپاں کر کے دیکھیں جو قتل
مرتد کے بارے میں دواوین احادیث میں موجود ہیں اور بتائیں کہ اس اصول کے رو سے
ہمیں کیا فیصلہ کرنا چاہئیے.کیا ان روایات کو لینا چاہئیے جن میں کسی قید کا ذکر نہیں یا اُن
روایات کی پیروی کرنی چاہئیے جن میں محاربہ کی شرط موجود ہے.پس ان احادیث سے کیا
نتیجہ نکلتا ہے؟ کیا یہی نتیجہ نہیں نکلتا کہ ہر ایک مرتد کے قتل کا حکم نہیں بلکہ صرف ایسے مرتد کا
جو محارب بھی ہو.خالص سوناوہ ہوتا ہے جو کسوٹی پر پرکھنے سے خالص ثابت ہو.اس نتیجہ کو
Page 210
207
بھی جس کسوٹی پر چاہو پر کھ کر دیکھ لو یہ ہر رنگ میں صحیح اور درست ثابت ہوگا.اس نتیجہ کی
صحت کی پہلی کسوٹی یہ ہے کہ یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بالکل مطابق ہے.تاریخ اسلام سے ثابت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک مرتد کو قتل کی سزا نہیں
دی بلکہ صرف ایسے مرتدین کو قتل کی سزادی جو محارب تھے جیسے عسکل یا عرینہ کے لوگ ،ابن
خطل مقیس بن صبابہ.پس یہ نتیجہ اس لئے درست ہے کہ یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
عمل کے عین مطابق ہے.اس نتیجہ کی صحت کی دوسری کسوٹی یہ ہے کہ یہ قرآن شریف کی
عام تعلیم اور روح کے عین مطابق ہے.کیونکہ جیسا میں مفصل طور پر ثابت کر چکا ہوں کسی
شخص کو محض ارتداد کے لئے قتل کرنا قرآن شریف کی تمام تعلیم کے خلاف ہے.اس نتیجہ کی
صحت کی تیسری کسوٹی یہ ہے کہ اگر مرتد کے قتل کے لئے محارب کی شرط کو لازم ٹھہرایا جائے
تو یہ حکم قرآن شریف کی ایک صریح آیت کے ماتحت آ جاتا ہے.جو اس کے صحیح ہونے کا
ایک یقینی ثبوت ہے.اور ہمیں حامیان قتل مرتد کی طرح یہ نہیں کہنا پڑتا کہ قرآن شریف اس
مسئلہ پر ساکت ہے اور وہ آیت جس سے مرتد کا محارب ہونے کی وجہ سے قتل ثابت ہوتا
ہے یہ ہے.إنَّمَا جَزَوا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا
أنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ
أو يُنْقَوامِنَ الْأَرْضِ (المائدة:34) جولوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ
کرتے ہیں اور فساد کی غرض سے ملک میں جنگ کی آگ بھڑ کانے کے لئے دوڑتے
پھرتے ہیں.ان کی مناسب سزا یہی ہے کہ ان میں سے ایک ایک کو قتل کیا جائے یا صلیب
پر لٹکا کر مارا جائے یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دیئے جائیں.یا انہیں
ملک سے نکال دیا جائے.اور یہ کہ قرآن شریف کے رو سے محارب کسے کہتے ہیں اس کے لئے ہمیں کسی لمبی بحث کی
Page 211
208
ضرورت نہیں.قرآن شریف نے خود اس کا فیصلہ فرما دیا ہے.سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ ایک
محارب کا ذکر کرتا ہے.اس مثال سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ محارب کا کیا مفہوم ہے.اللہ تعالیٰ
فرماتا ہے
وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ
الْمُؤْمِنِينَ وَارْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ الله وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ
وَلَيَحْلِفُ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى (التوبة: 107)
اور وہ لوگ جنہوں نے ایک مسجد نقصان پہنچانے اور کفر کی تبلیغ کرنے اور مومنوں میں
تفرقہ پیدا کرنے کے لئے بنائی ہے اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول سے لڑ چکا ہے اس
کے لئے کمین گاہ مہیا کرنے کے لئے.وہ ضرور قسم کھائیں گے کہ اس مسجد کے بنانے
سے ہمارا ارادہ صرف نیکی کرنا تھا.تاریخ سے ثابت ہے جس شخص کا آیت کریمہ میں ذکر ہے اور جس کو من حارب الله
ورسوله کا خطاب دیا گیا ہے وہ ابو عامر راہب تھا.درمنثور جلد ۳ صفحہ ۲۷۶ میں لکھا ہے.عن مجاهد في قوله والذين اتخذوا مسجدًا قال المنافقون وفى
قوله وارصادا لمن حارب الله و رسوله قال لأبي عامر الراهب.یہ ابی عامر راہب کیسا شخص تھا.اس کے لئے بحر محیط جلد 5 صفحہ 98 کی مندرجہ ذیل
عبارت ملاحظہ فرماویں.وحرضهم ابو عمرو الفاسق على بنائه حين نزل الشام هاربًا من
وقعة حنين فراسلهم في بنائه وقال ابنوا لي مسجدا فاني ذاهب الى
قیصراتي بجند من الروم فاخرج محمدا و اصحابه.ابو عمرو فاسق جب حنین کی لڑائی کے بعد بھاگ کر شام گیا تو اُس نے مدینہ کے
منافقوں کو اس مسجد کے بنانے کی ترغیب دی اور اس کے متعلق اُن سے خط و کتابت کی
Page 212
209
اور کہا کہ میرے لئے ایک مسجد بنواؤ.میں قیصر کے پاس جاتا ہوں اور روم سے ایک
66
لشکر لا کر محمد ( صلی اللہ علیہ وسلم ) اور اس کے ساتھیوں کو نکال دوں گا.“
پس ابو عامر کی مثال سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ محارب سے یہ مراد نہیں کہ ایک شخص
اسلام کو ترک کر دے اور مسلمانوں سے کوئی سروکار نہ رکھے اور نہ کسی مسلمان کو اذیت
پہنچائے بلکہ محارب سے مراد ایسا شخص ہے جو مسلمانوں کے مقابلہ کے لئے کھڑا ہو جائے
اور اُن کی تخریب کے در پے ہو.پس ایسا شخص قرآن شریف کے حکم مطابق تین سزاؤں
میں سے ایک سزا کا مستحق ہے.اُسے قتل کیا جاوے یا صلیب دیا جاوے یا اُس ملک میں
سے اُسے نکال دیا جاوے.حالات اور جرم کی کیفیت کے مطابق اُس کو سزا دی جاوے.حامیان قتل مرتد کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ نفس ارتداد ہی کا نام محاربہ ہے یعنی
جو شخص اسلام لانے کے بعد پھر کفر اختیار کرتا ہے وہ خواہ کسی مسلمان کو اذیت نہ پہنچائے اور
ایک بے ضرر انسان کی طرح زندگی بسر کرے پھر بھی وہ محارب ہی کہلائے گا.میں کہتا ہوں
که اگر محض ارتداد یعنی اسلام لانے کے بعد کفر اختیار کرنا محاربہ ہے تو کیا وجہ ہے کہ عام کفر
کو محاربہ نہ کہا جاوے.مرتد بھی ارتداد کے بعد ایک کافر کی زندگی اختیار کر لیتا ہے اور
دونوں کفر کے لحاظ سے ایک ہی حالت میں ہو جاتے ہیں.پس اگر محض مرتد محارب ہے تو
عام کا فر بھی محارب ہے کیونکہ موجودہ صورت میں دونوں مساوی ہیں.دونوں کفر کی حالت
میں ہیں اور دونوں مسلمانوں کو کسی قسم کی اذیت نہیں پہنچاتے بلکہ اُن کے ساتھ صلح کی
حالت میں رہنا چاہتے ہیں.پس کوئی وجہ نہیں کہ ایک کو اُس کے کفر کی وجہ سے قتل کیا جائے
اور دوسرے کو قتل نہ کیا جاوے.محض ارتداد کو محاربہ قرار دینا ایک زبر دستی ہے.جب تک
اُس سے کوئی ایسا فعل سرزد نہ ہو جو محار بہ کہلا سکے اس کو محارب نہیں کہہ سکتے.بحرالمحیط میں
لکھا ہےوقول ابن عباس، المحاربة هنا الشّرك وقول عروة الارتداد غير
Page 213
210
صحيح عند الجمهور.یعنی حضرت ابن عباس کا یہ قول کہ اس آیت کریمہ میں محاربہ
سے مراد شرک ہے اور عروہ کا یہ قول کہ اس آیت کریمہ میں محاربہ سے مراد ارتداد ہے جمہور
(بحر المحيط جلد 3 صفحہ 471)
کے نزدیک صحیح نہیں.بندہ کی رائے میں حامیان قتل مرتد کے اس قول کی تردید میں کہ محاربہ سے مراد محض
ارتداد ہے بحر المحیط کی مندرجہ بالا عبارت ہی کافی ہے.احادیث متعلق قتل مرتد کو یکجائی نظر سے دیکھنے سے جو نتیجہ نکلتا ہے یعنی یہ کہ صرف ایسے
مرتد کے قتل کا حکم ہے جو محارب ہو اس نتیجہ کی صحت کی چوتھی کسوٹی یہ ہے کہ قرآن شریف کی اس
آیت کریمہ کی تفسیر کہ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ (الانعام: ۱۵۲) أَن
احادیث کے ذریعہ کی جاتی ہے جن میں تین قسم کے لوگوں کے قتل کا حکم ہے اور جن کو میں
او پر نقل کر چکا ہوں اور اس آیت کریمہ کی تفسیر اللہ تعالیٰ خود بھی کرتا ہے جبکہ فرماتا ہے
مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا (المائدة: ۳۳) یہ
دوسری آیت پہلی آیت کی تفسیر کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ بالحق سے کیا مطلب ہے یعنی دو ہی
صورتوں میں کسی انسان
کا قتل کرنا جائز ہوسکتا ہے.ایک یہ کہ کسی انسان کو قصاص میں قتل کیا
جاوے.دوسرے یہ کہ وہ اس درجہ کے فساد کا مرتکب ہو جو اُس کو قتل کا مستوجب بناوے
اور ظاہر ہے کہ محض ارتداد ایسا فساد نہیں کہلا سکتا جو کسی کو مستوجب قتل بنا دے.کیونکہ اگر
محض ارتداد ہی انسان
کو مستوجب قتل بنا دیتا ہو تو پھر ایک کا فر بھی مستوجب قتل ٹھہرتا ہے
کیونکہ دونوں کفر کے لحاظ سے یکساں ہیں.ایک مرتد اُسی صورت میں فساد کا مرتکب کہلا
سکتا ہے جبکہ وہ محارب ہو جیسا کہ بعض احادیث میں تصریح کے ساتھ اس شرط کا ذکر کیا گیا
ہے.پس قرآن شریف کا جواز قتل کو صرف دوصورتوں میں محصور کر دینا یعنی ایک قصاص کی
صورت اور دوسری فساد فی الارض کی صورت ظاہر کرتا ہے کہ وہی مرتد واجب القتل ٹھہر سکتا
Page 214
211
ہے جو محارب ہو اور جو نتیجہ حادیث کو یکجائی نظر سے دیکھنے پر نکالا گیا ہے وہی نتیجہ صحیح اور درست
ہے.اس جگہ یہ امر بھی ذکر کر دینے کے قابل ہے کہ آیت کریمہ لَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ
الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ مکی آیت ہے.اور مفسرین بالحق کی تفسیر میں آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول نقل کرتے ہیں جس میں تین قسم کے لوگوں کے قتل کا ذکر ہے اور
جن میں سے ایک مرتد محارب ہے.پس معلوم ہو ا کہ مرتد محارب کے قتل کا حکم گویا مکہ میں
ہی نازل ہو چکا تھا.اس لئے جن مرتدین کو آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں قتل
نہیں کیا.ان کی نسبت یہ عذر نہیں ہوسکتا کہ ابھی قتل مرتد کا حکم نازل نہیں ہوا تھا.اس نتیجہ کی صحت کی پانچویں کسوٹی یہ ہے کہ حضرت ابن عباس آنحضرت
صلے اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ مرتدہ کوقتل نہ کیا جاوے.روى ابو حنيفة عن عاصم عن ابى رزين عن ابن عباس لا تقتل
النساء اذا من ارتددن
عینی شرح بخاری جلد 11 صفحہ 232
اگر محض ارتداد قتل کا موجب ہوتا تو عورت ومردونوں مساوی سمجھے جانے چاہئیے
تھے کیونکہ ارتداد میں دونوں یکساں ہیں.عورت
کو قتل سے مستثنی کرنا ظاہر کرتا ہے کہ
محض ارتداد کی سزا قتل نہیں بلکہ قتل کی سزا محارب ہونے کی وجہ سے دی جاتی تھی اور چونکہ
عورتیں عموماً محارب نہیں ہوتیں اس لئے ان کو قتل سے مستثنیٰ کیا گیا ہے جس طرح عام
جنگ کی صورت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کو مستثنی فرمایا.آپ جب کسی لشکر کولڑائی کے لئے روانہ فرماتے تو رخصت کرتے وقت آپ فرماتے :.اغزوا بسم الله في سبيل الله تقاتلون من كفر بالله لا تغلوا ولا
تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا ولا امرءة.(مؤطا امام مالك كتاب الجهاد باب النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو)
Page 215
212
یعنی خدا تعالیٰ کے نام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کرو.خیانت نہ کرو.نہ بد عہدی
کرو.نہ کسی مقتول کے ہاتھ پاؤں ناک، کان وغیرہ کاٹو اور نہ کسی بچے کو قتل کرو اور نہ
کسی عورت
کو قتل کرو.پس مرتد ہ عورت
کو نہ قتل کرنے کا حکم بھی ظاہر کرتا ہے کہ یہاں بھی وہی صورت ہے
جو عام جنگ میں ہوتی ہے اور مرتدہ کو اس لئے مستثنی کیا ہے کہ وہ محاربہ نہیں ہو سکتی.پس ثابت ہوا کہ صرف مرتد محارب
کو قتل کرنے کا حکم ہے نہ عام مرتدین کو.یہاں یہ ذکر کر دینا بھی ضروری ہے کہ اگر کوئی شخص حدیث مندرجہ بالا پر ابوحنیفہ کے
متفرد ہونے کا اعتراض کرے تو غلط ہے کیونکہ اس حدیث کو عبدالرزاق نے الشورى عن
عاصم کے طریق سے بیان کیا ہے.(ملاحظہ ہو مصنف عبدالرزاق.کتاب القصاص)
(۲) دارقطنی نے بھی اس حدیث کو ابی مالك النخعي عن عاصم کے طریق سے
نقل کیا ہے.(ملاحظہ ہو کتاب الحدود صفحہ 338)
(۳) دارقطنی نے اس حدیث کو شیبہ عن عاصم کے طریق سے بیان کیا ہے.كتاب الحدود صفحه (338)
(۴) نیز ابن ابی شیبہ نے اسی حدیث کو روایت کیا ہے عن وکیع عن ابی حنیفۃ.(تعليق المغنى شرح دار قطنی صفحہ 338)
نتیجہ مذکورہ بالا کی صحت کی چھٹی کسوٹی یہ ہے کہ جیسے قتل مرتد کے متعلق بعض
احادیث موجود ہیں جن کے ساتھ محاربہ کی شرط ہے ایسا ہی بعض ایسی احادیث بھی موجود
ہیں جن میں مرتد کے قتل کی ممانعت کی گئی ہے.عبدالرزاق نے مختلف احادیث عدم قتل مرتد
کے بارہ میں عطاء حسن.اور براہیم التھی سے نقل کی ہیں (دیکھو ھدایہ حاشیہ جلد 2 صفحہ 354
باب فی احکام المرتدین ).اور ابراہیم مخفی جو ایک مشہور فقیہ ہیں بعض دیگر علماء کی طرح
قتل مرتد کے مخالف ہیں.
Page 216
213
"
پس جب دونوں قسم کی احادیث موجود ہیں تو ان میں تطبیق کی راہ یہی ہے کہ قتل مرتد
کو اُس شرط کے ساتھ مشروط کیا جائے جو بعض احادیث میں صراحۃہ موجود ہے یعنی محارب
ہونے کی شرط.میں ناظرین کی توجہ کو ان احادیث کی طرف خصوصیت کے ساتھ پھیرتا
ہوں جو عبدالرزاق نے عدم مقتل مرتد کے بارے میں نقل کی ہیں.کیونکہ یہ احادیث حامیان
قتل مرتد کے اس دعوای کو پاش پاش کر دیتی ہیں جو کہتے ہیں کہ احادیث میں ہر ایک مرتد
کے قتل کا حکم دیا گیا ہے.خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب احادیث پر بھی یکجائی نظر ڈالی جائے تو اس سے یہی
ثابت ہوتا ہے کہ محض ارتداد کی سزا قتل نہیں ہے بلکہ صرف ایسے مرتدین کے قتل کا حکم ہے جو
محارب ہوں اور اُن کے لئے قتل کی سزا ارتداد کی وجہ سے مقرر نہیں کی گئی بلکہ محارب ہونے
کی وجہ سے.اور تاریخ کے دیکھنے سے ثابت ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا
عملدرآمد بھی اُسی کے مطابق تھا اور یہی راہ قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق ہے.اب بھی
اگر کوئی شخص اپنے اسی اسرار پر قائم رہے کہ محض ارتداد اور تنہا ارتداد کی سزا قتل ہے تو ایسا
شخص انصاف سے کام نہیں لیتا بلکہ ضد سے کام لیتا ہے اور ایسے شخص کو ہم حوالہ خدا کرتے
ہیں.حق کھل جانے کے بعد بھی جو شخص اس غلط عقیدہ پر قائم رہتا ہے تو وہ عمداً اسلام کو اور
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرتا ہے.ہم پر یہ اعتراض کیا گیا ہے کہ ہم قرآن شریف کو مقدم ٹھہرا کر اور اُس کو معیار صحت
قرار دے کر دو اوین حدیث کی ہتک کرتے ہیں.ہم دواوین حدیث کی ہتک نہیں کرتے
بلکہ اُن کو نہایت قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں.دیکھو یہ دواوین حدیث ہی کی برکت ہے کہ ہم
نے حدیث کے میدان میں بھی مدعیان قتل مرتد کو شکست دی.جن ہتھیاروں سے ہم نے
اس میدان میں مولوی صاحبان کو شکست دی ہے وہ اسی اسلحہ خانہ سے ہمیں میسر ہوئے ہیں
جو مد و نین حدیث نے ہمارے لئے تیار کر رکھا ہے.پس ہم ان محمد ثین کا تہ دل سے شکریہ
Page 217
214
ادا کرتے ہیں جنہوں نے اس قدر محنت اور تکلیف اُٹھا کرا حادیث کی چھان بین کی اور اُن
کو مدون کیا.آج انہی کی محنت اور جانفشانی کے طفیل ہم حامیان
قتل مرتد پر فتح حاصل کر
رہے ہیں.اگر یہ بزرگ ہمارے لئے یہ ہتھیار نہ چھوڑ جاتے تو ہم مولوی صاحبان کی غلطی
کا حدیث کے ذریعہ کس طرح ازالہ کرتے.اگر دواوین حدیث میں یہ الفاظ آج موجود نہ
ہوتے کہ رجل خرج محاربا لله ورسوله اور رجل يخرج من الاسلام
فيحارب الله عزّوجل ورسوله اور رجل حارب الله ورسوله وارتد عن
الاسلام.اور حارب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.اور التارك لدينه
المفارق للجماعة اور المارق لدينه الفارق للجماعة اور لا تقتل النساء
اذاهن ارتددن اور اگر عدم قتل مرتد کے متعلق احادیث موجود نہ ہوتیں اور اگر ایسے
مرتدین کے واقعات موجود نہ ہوتے جن کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود قدرت
کے
قتل نہ کیا.اگر صلح حدیبیہ کی شرائط احادیث میں موجود نہ ہوتیں جن کی رو سے آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد کیا کہ اگر کوئی مسلمان مرتد ہوکر مشرکین سے جاملے گا تو اس کا
مطالبہ نہ کیا جائے گا.اگر احادیث میں عبداللہ بن ابی سرح مرتد کی حضرت عثمان کی سفارش
پر معافی کا ذکر نہ ہوتا.اگر احادیث سے یہ ثابت نہ ہوتا کہ جن مرتدین کو آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے قتل کروایا اُن کو ارتداد کی وجہ سے نہیں بلکہ اُن کے جرائم کی وجہ سے قتل کروایا.اگر یہ سب زبر دست دلائل آج ہمیں دواوین حدیث میں لکھے ہوئے نہ ملتے تو ہم کس
طرح مرتد کے دعویداروں پر خود ان احادیث کے ذریعہ اُن کی غلطی واضح کر سکتے.پس ہم
دواوین حدیث کو نہایت عزت و احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں.کیونکہ اُن کے ذریعہ ہمیں
اس بحث میں بہت مددملی ہے.اسی طرح ہم دو اوین فقہ کو بھی نہایت ادب اور احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں اور اُن
فقہاء کے ہم شکر گزار ہیں جنہوں نے تحقیق حق کے لئے نہایت ہی قیمتی اصول قائم کئے
Page 218
215
ہیں.دیکھئے ان بزرگوں کے قائم کردہ اصول سے ہمیں کیسی مدد لی.دواوین حدیث میں
قتل مرتد کے متعلق ہمیں دو قسم کی احادیث میں ایک وہ جن میں ارتداد کا ذکر تھا یعنی ایسے
الفاظ تھے کہ من بدل دينه.من غير ديـنـه.ارتد عن الاسلام.كفر بعد
الاسلام اور دوسری وہ جن میں ارتداد کے ساتھ محاربہ کی بھی شرط تھی.اب ان دو قسم کی
احادیث کے متعلق فیصلہ کرنے میں فقہاء نے ہمیں کیسا زرین اصول بتایا کہ ایسی صورت
میں جن احادیث کے ساتھ شرط مذکور نہیں ہے وہاں بھی شرط کا وجود قرار دینا چاہئیے اور مطلق
کو مقید کے تابع کرنا چاہئیے.دیکھو ہمیں فقہاء کے اس مسلمہ اصول سے کیسی مددملی اور کس
طرح تمام احادیث کے متعلق صحیح فیصلہ کی راہ ہم پر کھولی گئی جو ہر ایک طالب حق کو تسلی بخشتی
ہے اور قرآن شریف کی تعلیم کے عین مطابق ہے.پس خدا تعالیٰ کا ہزار ہزار شکر ہے کہ جیسا
قرآن کے میدان میں قتل مرتد کے دعویداروں نے ہزیمت اٹھائی ایسا ہی احادیث کے
میدان میں بھی اُن کو خدا تعالیٰ کے فضل سے ہزیمت ہی اُٹھانی پڑی اور ہم اُن تمام ائمہ
حدیث وفقہ کے لئے دعا کرتے ہیں جن کی مدد سے ہمیں یہ فتح نصیب ہوئی.اللھم
اغفر لهم وارحمهم وادخلهم في عبادك المقربين.اب میں حامیان قتل مرتد کی خدمت میں ایک اور عرض کرتا ہوں.اگر اُن کو باوجود
ان تمام شہادتوں کے جومیں نے اوپر پیش کی ہیں اسی بات پر اصرار ہے کہ ارتداد کے لئے
بلا کسی شرط کے قتل کی سزا دینی چاہئیے تو میں ان کو ایک راہ بتا تا ہوں.اگر وہ اُس راہ پر چلیں
گے تو ان کا حدیث من بدله دینه فاقتلوہ پر
عمل بھی ہو جائے گا اور اُن کو اس بات کی بھی
ضرورت پیش نہیں آئے گی کہ تمام قرآن شریف کو منسوخ قرار دیں.اور وہ راہ یہ ہے کہ قتل
کے معنی صرف جان سے مارڈالنا نہیں ہیں بلکہ اس کے یہ بھی معنی ہیں کہ کالمقتول قرار
دینا اور مُردوں میں شمار کرنا.حضرت عمر نے سقیفہ کے دن سعد کی نسبت جس نے آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر خلافت حاصل کرنے کی کوشش کی.فرمایا اقتــلــوا سـعــدا
Page 219
216
قتله الله یہاں اقتلوا کے معنے یہ کئے گئے ہیں ای اجـعـلـوه كـمـن قتل
واحسبوه كمن مات وهلك ولا تعتدوا بمشهده ولا تعرجوا على قوله
(اقرب الموارد ونهاية لابن الأثير ) اسی طرح حضرت عمر نے فرمایا من دعا الى
امارة نفسه او غيره من المسلمين فاقتلوہ.یہاں بھی فاقتلوہ کے یہ معنے
کئے گئے ہیں ای اجعلوه كمن قتل ومات بان لا تقبلواله قولا وتقيموا له
دعوة (نهاية لابن الأثیر ) اسی طرح ایک اور حدیث ہے اذا بویع لخلیفتین فاقتلوا
لأخر منها یہاں بھی اقتلوا کے یہ معنے کئے گئے ہیں ای ابطلوا دعوته واجعلوه
كمن مات.(اقرب الموارد ونهاية لابن الأثير)
پس اگر ہمارے مخالف مولوی صاحبان کو اسی بات پر اصرار ہے کہ باقی تمام امور کو
بالکل نظر انداز کردیں اور الفاظ من بدل دینه فاقتلوا پر عمل کریں اور ان الفاظ میں کسی
قسم کی شرط داخل کرنا گناہ سمجھیں.یہاں تک کہ استتابہ کی شرط کو بھی ان الفاظ کی پیروی کر
کے چھوڑ دیں (حالانکہ استنتابہ کی شرط با وجود ان الفاظ میں مذکور نہ ہونے کے اُن کے
نزدیک مسلمہ ہے اور یہ امر ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ استنابہ کی شرط کو تو وہ اس حدیث کے
الفاظ میں اپنی طرف سے بڑھانا جائز قرار دیتے ہیں مگر محاربہ کی شرط جو قتل مرتد کی دوسری
احادیث میں صراحۃ موجود ہے اور قرآن شریف کی آیت کی رو سے ضروری ہے اس کا
بڑھانا حرام سمجھتے ہیں ) تو اُن کے لئے دوسری راہ کھلی ہے کہ فاقتلوہ کے وہ معنی لے لیں
جواحادیث مندرجہ بالا میں قتل کے لئے کئے گئے ہیں.اس طرح اُن کا اس حدیث پر بھی
عمل ہو جائے گا اور قرآن شریف کو بھی کالعدم قرار نہیں دینا پڑے گا.قتل مرتد اور صحابہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حامیان قتل مرتد نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے
Page 220
217
سوانح میں ایسی مثالوں کی تلاش کی ہے جن سے یہ ثابت ہو کہ صحا بہ بھی لوگوں کو محض ارتداد
کی سزا میں قتل کر دیا کرتے تھے اور نہایت خوشی کی بات ہے کہ جیسا کہ ابھی انشاء اللہ تعالیٰ
ناظرین پر روشن ہو جائے گا اس کوشش میں بھی اُن کو ایسی ہی تعلیخ نا کامی حاصل ہوئی ہے
جیسی کہ قرآن شریف اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دائرہ میں.میں ذیل میں وہ مثالیں نقل کرتا ہوں جو ان لوگوں نے صحابہ کے سوانح سے پیش
کی ہیں.(۱) حضرت ابوبکر نے مرتدین کے ساتھ جنگ کی.(۲) مسیلمہ کذاب کے ساتھ جنگ کی گئی.(۳) طلحه مدعی نبوت کے ساتھ جنگ ہوا.(۴) حضرت ابوبکر کے زمانہ میں ام قرفہ کو بوجہ ارتد ا قتل کیا گیا.(۵) حضرت علی نے زنادقہ کو جلا دیا.(۶) حضرت علی نے خوارج کے ساتھ جنگ کی.(۷) حضرت معاذ نے ایک مرتد یہودی کو قتل کرایا.صحابہ کے متعلق بحث کرنے سے پہلے میں حامیان
قتل مرتد سے ایک سوال کرنا
ضروری سمجھتا ہوں اور وہ سوال یہ ہے کہ جن دواوین حدیث و فقہ پر وہ لوگ اس قدر زور
دیتے ہیں اُن کا کسی صحابی کے قول یا فعل کے متعلق کیا فتو ی ہے.کیا کسی صحابی کا قول یا فعل
شریعت اسلام میں متفقہ طور پر حجت شرعیہ سمجھا گیا ہے.اس کے متعلق میں کسی اپنی رائے کا
اظہار نہیں کرتا صرف ان علماء سے پوچھتا ہوں کہ وہ خود بتائیں کہ اُن کے دواوین مسلّمہ و
مقبولہ میں صحابی کے قول یا فعل کے متعلق کیا فتوی دیا گیا ہے.اگر ان دواوین سے متفقہ طور
پر یہ ثابت ہو کہ ہر ایک صحابی کا ہر ایک قول اور ہر ایک فعل حجت شرعی ہے تب تو صحابہ کے
افعال و اقوال کی بحث ایک نہایت ضروری بحث سمجھی جائے گی.لیکن اگر ان دواوین کے
Page 221
218
متفقہ فتوای سے ایسا ثابت نہ ہو تو پھر یہ بحث ہمارے علماء کے لئے چنداں مفید نہ ہو گی.کیونکہ اگر بفرض محال وہ یہ ثابت بھی کر سکیں کہ کسی صحابی کا عمل اور قول قتل مرتد کی تائید میں
ہے تو اس کا وہ قول یا فعل حجت نہیں سمجھا جائے گا.اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے متعلق دواوین حدیث وفقہ کا کیا فتوی ہے.سو واضح
ہو کہ اہلحدیث کے نزدیک صحابی کا قول یا فعل کوئی حجت نہیں.جیسا کہ اصول حدیث کے
ومہ بہ مختصر الجرجانی میں السیدالشریف الجرجانی نے تحریر فرمایا ہے.”ماروى عن الصحابي من قول أو فعل متصلا كان او منقطعا ليس
بحجة على الاصح.اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قول یا فعل صحابی قطعا کوئی حجت
نہیں.کتاب کشف الاسرار شرح المنار جو اصول فقہ کی ایک مستند کتاب ہے اُس کی جلد 2
صفحہ 99 پر لکھا ہے.وانما قلّدنا الانبياء عليهم السلام لانا عرفنا عصمتهم عن الكذب
والخطأ بدلالة المعجزة فاتبعناهم لقيام دلالة العصمة وقد فقدت
هذه الدلالة فى غيرهم فلا يجب اتباعهم ولهذا قال الشافعي لا
نقلّد الصحابي لان قول الصحابي ليس بحجة اذ لوكان قوله حجة
فدعا الناس الى قوله كالنبي عليه السلام
یعنی ہم انبیاء علیہم السلام کی اس لئے تقلید کرتے ہیں کہ ہم نے اُن کے معجزات کے
ذریعہ یہ پہچان لیا ہے کہ وہ کذب اور خطا سے محفوظ تھے.پس ہم اُن کے معصوم ہونے کی
وجہ سے اُن کی اتباع کرتے ہیں اور یہ بات دوسروں میں نہیں پائی جاتی.پس اُن کا اتباع
واجب نہیں اور یہی وجہ ہے کہ شافعی رحمتہ اللہ علیہ کا قول ہے کہ ہم صحابی کی تقلید نہیں کرتے
کیونکہ صحابی کا قول حجت نہیں.کیونکہ اگر صحابی کا قول حجت ہوتا تو وہ اپنے قول کی طرف
Page 222
219
لوگوں کو اسی طرح دعوت دیتا جس طرح کہ نبی علیہ السلام اپنے قول کی طرف دعوت دیتا
ہے.پھر اُسی کتاب کے صفحہ ۰۰ اپر لکھا ہے:.وروى عـن عـمـر كـتـب الـى شـريـح ان اقض بكتاب الله ثم بسنة
رسول الله ثم برأيك ولم يقل بقولى.یعنی حضرت عمرؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے شریح کولکھا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب
کے ساتھ فیصلہ کرنا اس کے بعد سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور اُس کے بعد
اپنی رائے کے ساتھ اور یہ نہیں فرمایا کہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میرے قول
کے ساتھ فیصلہ کر.اور احناف کے نزدیک جوامر قیاس سے معلوم ہوتا ہے اُس میں صحابی کی تقلید ہرگز
ضروری نہیں.اور قتل مرتد ایک ایسا مسئلہ ہے جو قیاس کے ذریعہ سمجھا جا سکتا ہے.کیونکہ ہم
قرآن شریف کی آیات سے یہ قیاس کر سکتے ہیں کہ اسلام میں قتل مرتد جائز نہیں ہو سکتا
کیونکہ یہ قرآن شریف کی کئی آیات کے صریح خلاف ہے.پس جو امر قرآن شریف سے
قیاس کیا جا سکتا ہے اُس میں فقہ حنفیہ بھی صحابی کے قول یا فعل کو ضروری قرار نہیں دیتی اور
جن امور میں صحابی کی تقلید کا جواز بیان کیا گیا ہے اُن میں بھی اس جواز کی بنیاد یہ ٹھہرائی گئی
ہے کہ احتمال ہے کہ اُس صحابی نے یہ بات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو.اور اس
میں بھی خود حنفی مذہب کے علماء صحابی کی تقلید واجب قرار نہیں دیتے.قمر الا قمار شرح
نورالانوار میں لکھا ہے:.وفيه على ما افاد بحر العلوم انّ احتمال السماع ليس بموجب
والقياس حجة شرعيّة موجبة للعمل فكيف يترك بمجرد
الاحتمال.یعنی علامہ بحر العلوم نے اس بارہ میں یہ مفید بات کہی ہے کہ یہ احتمال کہ صحابی نے
Page 223
220
آنحضرت سے یہ سنا ہو گا اس بات کو واجب نہیں کرتا کہ صحابی کے قول کی تقلید کی جائے.کیونکہ قیاس ایک شرعی حجت ہے جس پر عمل کرنا ضروری ہے.پس ایسی چیز کو جس پر عمل
کرنا واجب اور ضروری ہے محض اس احتمال سے کہ شائد صحابی نے سنا ہو چھوڑا نہیں جا
سکتا.قمر الاقمارکا فاضل مصنف لکھتا ہے:.ولو كان ما قاله الصحابي مسموعا من الرسول صلى الله عليه
وسلم لرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم.....ولما لم يرفعه علم
انه من اجتهاده و اجتهاده و اجتهاد غيره متساويان في احتمال
الخطأ لعدم عصمته فلا يكون حجة وهذا فيما يدرك بالقياس واما
ما فيما لا يدرك بالقياس فيجوز ان الصحابي انما افتی به بخبر
ظنه دليلا ولا يكون كذلك فمع جوازان لا يكون دليلا كيف يلزم
غيره فلا يكون حجة
یعنی صحابی جو بات کہتا ہے اگر وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی ہوتی تو وہ اس
بات کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک مرفوع کرتا.اور جب اُس نے ایسا نہیں کیا تو
معلوم ہوا کہ وہ اپنے اجتہاد سے ایسا کہتا ہے اور صحابی اور غیر صحابی کا اجتہاد اس امر میں
برابر ہے کہ دونوں میں خطا کا احتمال ہے کیونکہ وہ معصوم نہیں.پس اُس کا قول حجت
نہیں.یہ ایسے امور کے متعلق ہے جو قیاس سے معلوم ہو سکتے ہیں اور جو امر قیاس سے
معلوم نہیں ہوسکتا اُس میں ممکن ہے کہ صحابی نے اُس بات کا فتویٰ ایسی خبر کی بنا پر دیا ہو
جس کو اُس نے دلیل خیال کر لیا حالانکہ وہ دلیل نہ ہو.پس جب یہ ممکن ہے کہ جس چیز کو
اُس نے دلیل خیال کیا ہے وہ حقیقت میں دلیل نہ ہو تو اس صورت میں اُس بات کا ماننا
کسی دوسرے پر کیونکر لازمی ہوسکتا ہے.نورالانوار میں لکھا ہے.
Page 224
221
وقال الشافعي رحمه الله لا يقلد احد منهم سواء كان مدركًا
بالقياس اولا لان الصحابة كان يخالف بعضهم بعضًا وليس احدهم
اولى من الأخر فتعين البطلان.یعنی شافعی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی صحابی کی تقلید ضروری نہیں.خواہ وہ امور ایسے
ہوں جو قیاس کے ذریعہ معلوم ہو سکتے ہوں یا ایسے ہوں جو قیاس کے ذریعہ معلوم نہ ہو
سکتے ہوں کیونکہ صحابہ کا خود ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف ہوا کرتا تھا.اور اس معاملہ
میں ایک کو دوسرے پر کوئی ترجیح نہیں ہے.پس ثابت ہوا کہ اُن
کی تقلید لازمی نہیں ہے.مندرجہ بالا حوالجات اس امر کے ثابت کرنے کے لئے کافی ہیں کہ دواوین فقہ و
حدیث کا اس امر پر اتفاق نہیں ہے کہ صحابی کا قول یا فعل حجت شرعیہ ہے.اس لئے اگر
مولوی صاحبان یہ ثابت بھی کر دیتے کہ کسی صحابی کا قول یا فعل اس امر کی تائید کرتا ہے کہ
مرتد کو محض ارتداد کی وجہ سے قتل کر دیا جائے تب بھی خود انہی کے مسلمہ دواوین کے رُو سے
اُن کی غرض پوری نہیں ہو سکتی تھی لیکن موجودہ بحث میں اعمال صحابہ کی جو مثالیں حامیان قبل
مرتد نے اپنے دعوی کی تائید میں پیش کی ہیں جب اُن پر واقعات کی روشنی میں نظر کی
جائے تو وہ مثالیں حامیان
قتل مرتد کی تائید نہیں کرتیں بلکہ تردید کرتی ہیں.قتل مرتد کے دعویداروں نے اپنے زعم میں سب سے زیادہ زبر دست مثال جو اپنے
دعوای کی تائید میں پیش کی ہے وہ اُس ارتداد کی مثال ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
وفات کے وقت وقوع میں آیا.ان کے نزدیک حضرت ابوبکر کا اپنے عہد خلافت کے
مرتدین کے ساتھ جنگ کرنا اس امر کا قطعی اور یقینی ثبوت ہے کہ اسلام میں محض ارتداد
کی سر اقتل ہے.ہمارے بھولے بھالے مولوی صاحبان عرب کے قبائل کی طبیعت سے بالکل
ناواقف ہیں.وہ ارتداد کے لفظ کو سن کر یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ مرتدین بالکل بے ضرر لوگ
Page 225
222
تھے.اُن کا اس سے زیادہ کوئی قصور نہ تھا کہ وہ زکوۃ خلیفہ وقت کو ادا کرنا ضروری نہیں سمجھتے
تھے اور نمازیں پڑھنا چھوڑ بیٹھے تھے.اس سے زیادہ ان کا کوئی قصور نہ تھا.نہ وہ مسلمانوں
سے لڑتے تھے اور نہ کسی کو کوئی گزند پہنچاتے تھے.اُن کو حکومت اسلامی سے کوئی پر خاش نہ
تھی بلکہ وہ خلیفہ وقت کے تابعدار اور معاون و مددگار تھے اور اسلامی حکومت کے ماتحت وہ
امن اور فرمانبرداری سے زندگی بسر کرنے کے خواہاں تھے.پس اگر اُن کا کوئی قصور تھا تو
یہی تھا کہ زکوۃ اور نماز کو وہ ضروری نہ سمجھتے تھے.اگر مولوی صاحبان
کا ایسا خیال ہے تو یہ ان
کا بھولا پن ہے.وہ اُس زمانہ کے تمدن اور اُن لوگوں کے طرز سے بے خبر ہیں.اُن کے
ارتداد کے یہ معنی نہ تھے کہ اُن کو صرف مذہبی اختلاف تھا اور نہ اپنی ملکی زندگی میں وہ اس
سلطنت اسلامی کے خیر خواہ اور تابعدار تھے جس کی رعایا ہونے کا وہ مدینہ میں اپنے
نمائندوں اور وفود کے ذریعہ اعلان کر چکے تھے.بلکہ اُن کے ارتداد کے عملی رنگ میں یہ
معنے تھے کہ اُنہوں نے اس سلطنت اسلامی جس کی ماتحتی کا جوا وہ اپنی گردنوں پر رکھ چکے
ا
تھے بغاوت اختیار کی.یہی وجہ ہے کہ ارتداد کے ساتھ ہی انہوں نے اسلام کے خلاف
تلوار اُٹھالی اور جولوگ اُن میں سے اسلام پر قائم رہے اُن کو قتل کیا اور مسلمانوں کے ساتھ
جنگ کرنے کیلئے لشکر جمع کرنے شروع کر دیئے.اسلامی سلطنت سے اپنے آپ کو آزاد کر
لیا اور خود دارالسلطنت اسلامیہ پر حملہ کیا اور اس کا محاصرہ کیا اور مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا
دینا چاہا.اگر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ایسے لوگوں کے ساتھ جنگ کیا اور اُن کو
تلوار کے ساتھ زیر کیا اور باغیوں کی سرکوبی کی تو اس سے یہ استدلال نہیں ہوسکتا کہ اسلام
میں محض ارتداد کی سزا قتل ہے.اگر ملک میں امن تھا اور مرتدین کو صرف مذہبی اختلاف تھا
اور بغاوت کا کوئی ارادہ نہ تھا تو پھر کیا وجہ ہے کہ حضرت اُسامہ بن زید کے لشکر کی روانگی کے
وقت عمائد مہاجرین و انصار حضرت صدیق اکبر کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے اور
عرض کی کہ ایسے خطرہ کے وقت میں اس لشکر کا روانہ کرنا مصلحت کے خلاف ہے.
Page 226
223
میں پوچھتا ہوں کہ اگر وہ ارتداد جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد
قبائل عرب میں نمودار ہوا بالکل ایک بے ضرر تحریک تھی تو پھر کیا وجہ ہے کہ حضرت اسامہ
رضی اللہ عنہ نے روانگی سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو حضرت ابو بکر کے پاس بھیجا
اور مع لشکر واپس آنے کی اجازت مانگی اور وجہ پیش کی کہ
ان معى وجوه الناس وجلتهم ولا امن على خليفة رسول الله وحرم
رسول الله والمسلمين ان يتخطفهم المشركون.یعنی میرے ساتھ بڑے بڑے آدمی ہیں اور مجھے ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ مشرکین خلیفہ
وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم محترم اور دوسرے مسلمانوں پر حملہ نہ کر دیں.میرے خیال میں حامیان
قتل مرتد کو اس امر کے یقین دلانے کا کہ وہ مرتدین کی
جماعت جن کے خلاف حضرت ابو بکڑ نے قتال کیا ایک بے ضرر جماعت نہ تھی.سہل ترین
طریق یہ ہے کہ ان مرتدین کے حالات میں سے کچھ صفحہ تاریخ سے نقل کر کے اُن کی
خدمت میں پیش کیا جائے تا ان کو معلوم ہو کہ یہ لوگ بے ضرر بڑے نہ تھے جیسا مولوی
صاحبان نے اپنی سادگی سے سمجھ رکھا ہے بلکہ وہ خونخوار بھیڑیے اور وحشی درندے تھے اور
اگر اُن کے خلاف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے تلوار اٹھائی تو اس سے ہرگز یہ ثابت
نہیں ہوتا کہ اسلام میں محض ارتداد اور تنہا ارتداد کی سزا قتل ہے.(۱) جیسا کہ خوف کیا گیا
تھا.لشکر اُسامہ کی روانگی کے بعد مدینہ کے قرب و جوار کے مرتدین نے مدینہ پر حملہ کیا اور
کئی دن تک محاصرہ کئے ہوئے پڑے رہے.حضرت ابوبکر نے انہی تھوڑے سے آدمیوں
کو جوشکر اُسامہ سے بیچ رہے تھے ساتھ لے کر محاصرین پر حملہ کر کے ان کو منتشر کیا.طبری میں لکھا ہے:.و كان اول من صادم عبس و ذبيان عاجلوه فقاتلهم قبل رجوع
طبری جلد 4 صفحہ 1872)
أسامة.
Page 227
224
یعنی سب سے پہلے جن قبیلوں نے مدینہ پر حملہ کیا وہ عبس وذبیان تھے.انہوں نے پہلے
حضرت ابوبکر پر حملہ کیا اور اُسامہ کی واپسی سے پہلے حضرت ابوبکر نے ان کے ساتھ
جنگ کی.ابن خلدون نے لکھا ہے فعاجلته عبس و ذبيان ونزل آخرون( بنو اسد.فزاره غطفان طى ثعلبه بنو کنانه وغيرهم - تاریخ طبری جلد 4 صفحه 1873 الی
صفحہ 1876) بذى القصه ابن خلدون جلد ۲ صفحہ ۶۵) یعنی عبس و ذبیان قبیلوں نے
پہلے حضرت ابوبکر" پر حملہ کیا اور دوسری قومیں یعنی بنو اسد.فزارہ.غطفان طی.تعلیہ.بنو کنانہ وغیرھم ذی القصہ میں آکر جمع ہو گئے.خمیس میں لکھا ہے:.واقبل خارجة بن حصن بن حذيفة ابن بدر فكان ممن ارتد في خيل
من قومه الى المدينة يريد ان يخذل الناس عن الجزوج او يصيب
عزّة فيغير فاغار على أبي بكر ومن معه وهم غافلون.تاریخ خمیس جلد 2 صفحہ 204 مطبوعہ 1283ھ)
یعنی خارجہ بن حصن جو مرتدین میں سے تھا اپنی قوم کے کچھ سوار لے کر مدینہ کی طرف
بڑھا تا کہ صحابہ کے نکلنے سے قبل ہی غفلت میں چھاپہ مارے اس لئے اُس نے حضرت
ابوبکر اور آپ کے ساتھ کے مسلمانوں پر چھاپہ مارا جب کہ مسلمان بے خبر تھے.بعض مرتدین نے مدینہ میں وفود بھیجے تا نماز وز کوۃ میں معافی مل جائے اور جب
حضرت ابوبکر نے صاف جواب دے دیا اُن لوگوں نے مدینہ پر حملہ کیا.ادھر حضرت ابوبکر
نے اُن وفود کے چلے جانے کے بعد مسلمانان مدینہ کو اکٹھا کر کے یوں خطاب کیا.ان الارض كافرة وقد رأى وفدهم منكم قلة وانكم لا تدرون أليلا
تؤتون ام نهارًا و ادناهم منكم على بريد وقد كان القوم مائلون ان
Page 228
225
لقبل منهم ونوادعهم وقد ابينا عليهم ونبذنا اليهم عهدهم
فاستعدوا واعدو فما لبثوا الا ثلاثا حتى طرقوا المدينة غارة مع
الليل وخلفوا بعضهم بذى حُسى ليكونوا لهم رداً -
تاریخ طبری جلد 4 صفحہ 1875)
یعنی تمام ملک اب کا فر ہے اور اُن کے وفد نے تمہاری قلت تعداد کو دیکھ لیا ہے.تمہیں
معلوم نہیں کہ رات کے وقت ان پر حملہ کریں یا دن کو اور ان میں سے قریب ترین لوگ تم
سے ایک منزل کے فاصلہ پر ہیں.وہ چاہتے تھے کہ ہم اُن کی بات قبول کر کے اُن سے
معاہدہ کر لیں.اور ہم نے اس سے انکار کیا.پس تم اُن کے حملہ کے لئے تیار ہو جاؤ.اور تین دن ہی گزرے تھے کہ اُنہوں نے رات کے وقت مدینہ پر آکر چھاپہ مارا اور
ایک جماعت کو ذی حسی میں چھوڑ آئے تا وہ اُن کے مددگار ہوں.حامیان قتل مرتد نوٹ کریں کہ یہ چھا پہ مارنے والی جماعت وہی لوگ تھے جوز کو ۃ
معاف کرانے کے لئے مدینہ آئے تھے.جب درخواست نامنظور ہوئی تو تین دن کے اندر
مدینہ پر حملہ کر دیا.مندرجہ بالا حوالجات سے ناظرین نے دیکھ لیا ہے کہ مرتدین نے مسلمانوں پر حملہ
کرنے میں پیشدستی کی اور اُن کو قلیل اور کمز ور دیکھ کر سمجھا کہ ہم مدینہ کو فتح کر لیں گے اور
اسلامی سلطنت کے پایہ تخت پر قابض ہو جائیں گے.مگر خدا تعالیٰ نے اپنے وعدہ کے
مطابق خلیفہ وقت کی تائید کی اور دشمنوں کو خائب و خاسر لوٹا دیا.مرتدین نے صرف مدینہ ہی پر حملے نہیں کئے تھے بلکہ انہوں نے مرتد ہوتے ہی
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد معا أن صادق الایمان مسلمانوں
کو بھی تہ تیغ
کر دیا جوان قوموں میں بستے تھے اور جو باوجود اپنی قوم کے مرتد ہو جانے کے اسلام پر قائم
رہے تھے چنانچہ ابن خلدون میں لکھا ہے:.
Page 229
226
فوثب بنو ذبيان وعبس على من فيهم من المسلمين وفعل ذالك
غيرهم من المرتدين (ابن خلدون جلد ۲ صفحه ۶۶)
یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سنتے ہی بنو ز بیان اور عبس نے لوگوں پر
حملہ کر دیا جو اُن میں مسلمان تھے.اور یہ کام صرف بنو ذ بیان اور عبس نے ہی نہ کیا بلکہ
اُن کے سوا جو دوسری مرتد قو میں تھیں اُنہوں نے بھی اسی طرح اُن مسلمانوں کو قتل کر
دیا جو اُن میں آباد تھے.طبری نے لکھا ہے:.فوثب بنو ذبيان وعبس على من فيهم من المسلمين وقتلوهم كل
قتلة وفعل من وراء هم فعلهم.(تاریخ طبری جلد 4 صفحہ 1877)
یعنی جو نہی آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر پہنچی بنو ذبیان اور عبس اُن
مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے جو اُن میں رہتے تھے اور اُن کو ہر ایک طریق سے قتل کیا اور
جو قو میں اُن کے علاوہ بستی تھیں اُنہوں نے بھی ایسا ہی کیا.یعنی انہوں نے بھی ایسے
لوگوں
کو قتل کر دیا جو اسلام پر قائم رہے.اب حامیان
قتل مرتد فرما دیں کہ کیا ان لوگوں کا جرم صرف یہی تھا کہ اُنہوں نے
ارتداد اختیار کیا اور کیا ان لوگوں کے واقعات سے اُن کا یہ دعوی ثابت ہوتا ہے کہ اسلام
میں محض ارتداد اور تنہا ارتداد کی سزا قتل ہے.اگر ان لوگوں کا جرم محض ارتداد نہ تھا بلکہ انہوں
نے کھلم کھلا بغاوت اختیار کی اور مسلمانوں کو قتل کیا اور اس بات کی کوشش کی کہ مسلمانوں کو
صفحہ ہستی سے مٹادیں اور اسلامی سلطنت کو جڑ سے اکھیڑ ڈالیں اور اسلام کو نابود کریں.تو
پھر اے حامیان قتل مرتد کیا یہ افسوس کا مقام نہیں کہ آپ ایسے لوگوں کی مثال پیش کر کے یہ
ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اسلام میں محض ارتداد اور تنہا ارتداد کی سزا قتل ہے.کیا ایسی مثالوں
کے پیش کرنے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ لوگوں کے ہاتھوں میں کوئی ثبوت نہیں اس
Page 230
227
لئے واہیات باتیں پیش کر رہے ہو.کچھ تو اپنی مولویت کے نام کی شرم کرنی چاہئیے.میں اوپر ذکر کر چکا ہوں کہ پیشتر اس کے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ایسی قوموں
کی گوشمالی کے لئے لشکر مختلف اطراف میں روانہ کریں ان میں سے بعض نے بغیر حضرت
ابوبکر کے حملہ کے خود بخود مدینہ پر حملہ کیا.اس سے ناظرین ان مرتدین کے ارادوں کا
اندازہ لگا سکتے ہیں.لیکن دو وجہوں سے عام طور پر مرتدین مدینہ پر چڑھائی کرنے سے
ڑکے رہے.ایک وجہ یہ تھی کہ جن اقوام نے مدینہ پر حملہ کیا اُن پر حضرت ابو بکر اور آپ
کے ساتھیوں نے نہایت شجاعت اور دلیری سے حملہ کر کے اُن کو منتشر کر دیا.اس سے
دوسری قوموں پر مسلمانوں کا رُعب قائم ہو گیا.دوسرے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
وفات پر معا لشکر اُسامہ کے روانہ ہو جانے سے یہ ایک بڑا بھاری فائدہ پہنچا کہ عرب کی
اقوام نے اس سے یہ نتیجہ نکالا کہ مسلمانوں کی طاقت بہت زبر دست اور قوی ہے تب ہی تو
انہوں نے عرب کے مرتدین کی کچھ پرواہ نہیں کی اور بلا کسی خوف کے ایک بھاری لشکر ملک
شام کی طرف روانہ کر دیا ہے.صاحب تاریخ الکامل لکھتے ہیں.وكان انفاذ جيش اسامة اعظم الامور نفعًا للمسلمين فان العرب
قالوا لولم يكن بهم قوّة لما أرسلوا هذا الجيش فكفّوا عن كثير
ما كانوا يريدون ان يفعلوه.تاریخ الکامل جلد 2 صفحہ 139 )
یعنی لشکر اسامہ کے بھیجا جانے سے مسلمانوں کو بہت ہی بڑا فائدہ پہنچا کیونکہ عرب
قوموں نے کہا کہ اگر مسلمانوں میں طاقت اور قوت نہ ہوتی تو وہ ایسے وقت میں اس
لشکر کوروانہ نہ کرتے.پس اس خیال سے وہ اپنے بہت سے بدا را دوں سے رُک گئے.اس حوالہ سے بھی صاف ظاہر ہے کہ تمام مرتد قبائل مدینہ پر حملہ کرنا چاہتے تھے.اور صرف اس وجہ سے رُک گئے کہ لشکر اُسامہ کی روانگی سے انہوں نے نتیجہ نکالا کہ مسلمانوں
Page 231
228
میں بہت بڑی طاقت اور قوت ہے.اگر ناظرین تفصیل واران قوموں کے حالات جن پر
حضرت ابو بکر نے لشکر اُسامہ کی واپسی کے بعد فوج کشی کی کتب تاریخ میں مطالعہ فرما دیں تو
اُن پر روز روشن کی طرح یہ امر ظا ہر ہو جائے گا کہ یہ قو میں صرف ارتداد کی مرتکب نہیں ہوئی
تھیں بلکہ ان سب قوموں نے سلطنت اسلام کے خلاف بغاوت اختیار کی تھی اور اگر ان پر
فوج کشی نہ کی جاتی تو یہ لوگ اس بات پر تلے ہوئے تھے کہ مسلمانوں کا نام ونشان دنیا سے
مٹادیں.روز بروز ان کی جمعیت بڑھتی جاتی تھی اور اگر ان اقوام کو کچھ مزید مہلت مل جاتی
تو ان کی جمعیت اس قدر مضبوط ہو جاتی اور ان کا حوصلہ اس قدر بڑھ جاتا کہ تمام گردو نواح
کے مسلمانوں کو تہ تیغ کر کے آخر مدینہ پر حملہ آور ہوتے.پس ضروری تھا کہ مسلمان ان پر
حملہ آور ہو کر ان کی جمعیت کو توڑتے اور اس آگ کو جو تمام اطراف میں پھیل کر مسلمانوں
کی ہستی کو خطرہ میں ڈال رہی تھی بجھا دیتے.ہر ایک شخص جو تاریخ سے کچھ بھی واقفیت رکھتا
ہے اس بات کو تسلیم کرے گا کہ اگر اس وقت حضرت ابوبکران مرتد اقوام کے ساتھ قتال نہ
کرتے تو آج نہ اسلام نظر آتا اور نہ مسلمانوں کا وجود پایا جاتا.میں یہاں ان تمام قبائل کی کارروائیاں الگ الگ نقل نہیں کر سکتا.صرف عینی کی
شہادت پر اکتفا کرتا ہوں جو اُس نے تمام قبائل کے متعلق مجموعی طور پر دی ہے.عینی میں لکھا ہے:.وانما قاتل الصديق مانعى الزكوة لأنهم امتنعوا بالسيف ونصبوا
الحرب للامة.( عینی جلد 11 صفحہ 236)
یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے مانعین زکوٰۃ سے اس لئے قتال کیا کہ اُنہوں
نے تلوار کے ذریعہ سے زکوۃ کو روکا اور مسلمانوں کے لئے جنگ برپا کی.اس شہادت سے ظاہر ہے کہ جنگ کی ابتدا مانعین زکوۃ کی طرف سے ہوئی.یعنی
نہ صرف ان لوگوں نے زکوۃ کے ادا کرنے سے انکار کیا بلکہ مسلمانوں کے خلاف خود ہی
Page 232
229
تلوار اُٹھائی اور جنگ کی بنیاد ڈالی.جیسا کہ میں ابھی بیان کر چکا ہوں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر جن قبائل
نے ارتداد اختیار کیا اُن کا ارتداد مذہبی اختلاف تک محدود نہ تھا بلکہ اُنہوں نے سلطنت
اسلامی سے بغاوت اختیار کی.تلوار کو ہاتھ میں لیا.مدینہ منورہ پر حملہ کیا اپنی اپنی قوم کے
مسلمانوں
کو قتل کیا.آگ میں ڈالا اور اُن کا مثلہ کیا.جیسا کہ طبری کی مندرجہ ذیل عبارت
سے ظاہر ہے.ولم يقبل خالد بعد هزيمتهم من احد من اسد وغطفان ولا هوازن
ولا سليم ولاطئ الا ان ياتوه بالذين حرقوا ومثلوا وعدوا على اهل
الاسلام في حال ردّتهم.(تاریخ طبری جلد 4 صفحه 1900
وايضا ابن خلدون جلد 2 صفحہ 71 و تاریخ الکامل جلد 2 صفحہ 149 بتغائر الالفاظ )
یعنی جب بنی اسد اور غطفان اور ہوازن اور بنی سلیم اور بنی طئی کو شکست ہوئی تو خالد
رضی اللہ عنہ نے ان کو معافی دینے سے انکار کیا جب تک وہ ان لوگوں کو پیش نہ کریں
جنہوں نے مرتد ہونے کے بعد مسلمانوں کو آگ میں ڈال کر جلایا اور اُن کے ہاتھ
پاؤں ناک وغیرہ کاٹے اور اُن پر ظلم کئے.اسی طرح تاریخ سے ثابت ہے کہ مرتدین نے اپنے اپنے علاقوں.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عمال کو نکال دیا اور بعض جگہ مرتدین نے جدا گانہ بادشاہت
بھی قائم کر لی.یا قائم کرنے کی کوشش کی.مثلاً ابن خلدون نے لکھا ہے.وارتدت ربيعة ونصبوا المنذر بن النعمان بن المنذر وكان يسمى
المغرور فاقاموه ملكا كما كان قوم بالحيرة.ނ
( ابن خلدون جلد 2 صفحہ 76 و تاریخ طبری جلد 4 صفحہ 1960 )
یعنی بنو ربیعہ نے (جو بحرین کا ایک قبیلہ تھا) ارتداد اختیار کیا اور مرتد ہونے کے بعد
Page 233
230
المنذر بن النعمان کو کھڑا کیا جو مغرور کے خطاب سے مشہور تھا اور اُس کو اپنا بادشاہ بنالیا.پس ان حالات میں یہ کہنا کہ عہد خلافت اولیٰ میں مسلمانوں کا مرتدین سے قتال
کرنا یہ ثابت کرتا ہے کہ اسلام میں محض ارتداد کیلئے قتل کی سزا مقرر کی گئی ہے ایک باطل
دعوی ہے اور جو شخص ایسا دعوی کرتا ہے وہ یا تو تاریخ اسلام سے قطع نا واقف یا عمداد نیا کو
دھوکہ دینا چاہتا ہے.مسیلمہ کذاب
اسی طرح قائلین قتل مرتد نے مسیلمہ کذاب کے واقعہ کو پیش کر کے یہ ثابت کرنا چاہا
ہے کہ اسلام میں محض ارتداد کی سزا قتل ہے.اور اعتراض کیا ہے کہ اگر لا اکراہ فی
الدین کے یہی معنی درست ہیں کہ دین کے بارہ میں کسی چیز پر جبر نہیں کرنا چاہیئے تو مسیلمہ
کذاب سے کیوں جنگ کی گئی اور اس کو کیوں آزاد نہ چھوڑا گیا؟
اقول اگر اُس کا صرف رسالت کا ہی دعویٰ ہوتا اور ملکی معاملات میں وہ کوئی دخل
نہ دیتا تب تو بے شک حامیان
قتل مرتد کا اعتراض قابل غور ہوتا.مگر یہاں تو معاملہ ہی
برعکس ہے.ان بزرگان کو اگر تاریخ اسلام سے کچھ بھی آگا ہی ہو تو اُن کو معلوم کرنا چاہئیے
کہ مسیلمہ کذاب کی اصل غرض حکومت سے تھی.نبوت کا دعوی تو صرف ایک ذریعہ تھا جو
اس غرض کے حاصل کرنے کے لئے استعمال کیا گیا.وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
وقت میں بنو حنیفہ کے وفد کے ساتھ مل کر مدینہ میں آیا اور یہ شرط پیش کی کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد مجھے خلیفہ بنادیں تو میں آپ کی اتباع کرلوں گا.آپ نے ایک
کھجور کی چھڑی اٹھا کر فرمایا کہ تجھے اس چھڑی کے برابر بھی نہیں دیا جائے گا.یہ کہہ کر آپ
اُس کے پاس سے چلے آئے.واپس جا کر اس نے نبوت کا دعوی کیا اور کہا کہ نصف ملک
ہمارا ہے اور نصف ملک قریش کے لئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں
Page 234
231
مندرجہ ذیل مضمون کا خط لکھا:.من مسيلمة رسول الله الى محمد رسول الله.سلام عليك فانی
قد اشركت في الامر معك وان لنا نصف الارض ولقريش نصف
الارض ولكن قريشا قوم يعتدون.(ملاحظہ ہو تاریخ طبری جلد 4 صفحہ 1849)
یعنی میں آپ کے ساتھ اس امر میں شریک کیا گیا ہوں.نصف ملک ہمارا ہے اور
نصف قریش کا.آپ نے جواب میں لکھوایا :.إِنَّ الْأَرْضَ لِلهِ يُوْرِثُهَا مَنْ تَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ
وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ (الاعراف:129)
کہ ملک تو اللہ کا ہے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث کر دیتا ہے اور
اچھا انجام متقیوں کے ہی ہاتھ رہتا ہے.بعد دعوای نبوت حجر اور الیمامہ پر حاکم بن گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر
کردہ والی شمامہ بن اثال کو نکال دیا ( خمیس جلد 2 صفحہ 177) سجاح باغیہ کے ساتھ جو
مسلمانوں سے لڑنے کا ارادہ رکھتی تھی اتحاد کر لیا اور اسے کہا اكل بقومى وقومك العرب
یعنی اپنی اور تیری قوم کی مدد سے تمام عرب کو فتح کرلوں گا ( تاریخ طبری جلد 4 صفحہ 1918)
اس کو بعد از دعوای نبوت دو مدنی صحابی ملے.حبیب بن زید اور عبداللہ بن وہب الاسلمی.اس نے دونوں
کو پکڑ کر اپنی نبوت منوانی چاہی.عبداللہ تو مرتد ہو گیا مگر حبیب نے نہ مانا تو
اُسے عضو عضو کاٹ کر آگ میں جلا دیا ( تاریخ خمیس جلد 2 صفحہ 241)
کیا ان حالات میں حامیان قتل مرتد کہہ سکتے ہیں کہ مسیلمہ سے محض ارتداد کی وجہ سے
قبال کیا گیا اور یہ کہ اس کے واقعہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسلام میں محض ارتداد کی سزا قتل ہے.مسیلمہ کے ساتھ اس قدر جمعیت اکٹھی ہو گئی تھی کہ جب یمامہ میں خالد بن ولید
Page 235
232
کے ساتھ اس کی جنگ ہوئی تو صرف بنو حنیفہ کے چالیس ہزار سپاہی اس کے ساتھ موجود
تھے اور ایسی خونریز لڑائی ہوئی کہ مسلمانوں نے ایسی سخت لڑائی کبھی پہلے نہیں دیکھی تھی.مگر
حامیان قتل مرتد مسیلمہ کو صرف ایک بے ضرر انسان ظاہر کرتے ہیں.اور اعتراض کرتے
ہیں کہ لا اکراہ فی الدین کے منشاء کے ماتحت اُس کو بالکل آزاد چھوڑ دینا چاہیے تھا.اسی طرح حامیان
قتل مرتد نے طلیحہ مدعی نبوت کی مثال کو پیش کیا ہے اور اُس سے
یہی نتیجہ نکالتے ہیں کہ اسلام میں محض ارتداد کی سزا قتل ہے.یا تو یہ مولوی صاحبان خود تاریخ سے قطعاً نا واقف ہیں یا دوسروں کو نا واقف سمجھ کر
دنیا کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں.اگر ان دونوں باتوں میں سے ایک بات بھی
درست نہ ہو تو پھر یہ سمجھ میں نہیں آسکتا کہ کیوں مسیلمہ اور طلیحہ کی مثالوں کو اس دعوای کے
ثبوت میں پیش کیا جاتا ہے کہ اسلام میں محض ارتداد کی سزا قتل ہے.کیونکہ یہ لوگ محض مرتد
ہی نہیں تھے بلکہ انہوں نے اسلام کے خلاف تلوار اٹھائی اور مسلمانوں کی جماعت کو نا بود
کر کے خود ملک عرب پر قبضہ کرنا چاہا.مسیلمہ کے حالات میں مختصر اوپر بیان کر چکا ہوں.اب طلیحہ کے حالات سنئے !
طلیحہ بن خویلد اسدی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ہی مرتد ہو گیا
تھا.سمیرا مقام میں قیام پذیر ہوا اور وہاں اس نے اپنے اردگر دایک لشکر جمع کیا.آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ اور بھی مضبوط ہو گیا.قبائل غطفان و ہوازن
وطے اس کے ساتھ ہو گئے.جن لوگوں نے مدینہ پر پیش دستی کر کے چھاپہ مارا تھا ان کے دو
حصے ہو چکے تھے.ایک وہ جو ابرق میں مقیم تھے اور دوسرے وہ جو ذکی القصہ میں تھے.طلیحہ
نے اپنے بھائی کو مؤخر الذکر لوگوں پر افسر مقرر کر کے بھیجا.عبس و ذبیان کو جب حضرت
ابوبکر نے مدینہ کے پاس شکست دی تو وہ بھی طلیحہ سے آکر ملے اور اسی طرح بنوفزازہ نے
مسلمانوں کو طرح طرح کی تکلیفیں دیں بعض کا مثلہ کیا بعض کو آگ میں جلا دیا.جیسا کہ
Page 236
233
طبری کے مندرجہ ذیل اقتباس سے ظاہر ہے.وو
ولم يقبل (خالد بعد هزيمتهم من احد من اسد وغطفان ولا
هوازن ولا سليم ولاطئ الا ان ياتوه بالذين حرقوا ومثلوا وعدوا
على اهل الاسلام في حال ردّتهم
"
تاریخ طبری جلد ۴ صفحه ۱۹۰۰ و ایضاً ابن خلدون جلد ۲ صفحہ اے و تاریخ الکامل جلد ۲ صفحه ۱۴۹ بتغایر الالفاظ )
مندرجہ ذیل اقتباس سے ظاہر ہے کہ بنی اسد اور غطفان اور ہوازن اور سلیم اور بنی
طی کے لوگوں نے مسلمانوں کو آگ میں ڈال کر جلایا اور ان کا مثلہ کیا.اور یہ سب قبائل وہ
ہیں جو مرتد ہو کر طلیحہ کے ساتھ مل گئے تھے.اسی طرح عکاشہ بن محصن اور ثابت بن اقرم انصاری گردو نواح کی گشت اور ادھر
ادھر کی تگ و دو کو نکلے تو ان کی غفلت میں طلیحہ اور اس کے بھائی نے انہیں قتل کر دیا اور
مسلمانوں نے ان کی لاشوں کو روندا ہوا پایا.مندرجہ بالا واقعات کی تصدیق کے لئے ملاحظہ
ہوں طبری جلد 4.تاریخ الکامل جلد 2 اور خمیس جلد 2.اب ناظرین خود ہی فیصلہ فرماویں کہ کیا طلیحہ کا جرم صرف یہی تھا کہ اس نے ارتداد
اختیار کیا یا وہ دوسرے جرموں کا بھی مرتکب ہو چکا تھا؟ وہ نہ صرف خود باغی تھا بلکہ وہ
دوسرے باغیوں کا ملجاء اور ماوی بنا ہوا تھا.اور اس کے لوگوں نے اور خود اس نے
مسلمانوں کو قتل کیا.کیا ان حالات میں یہ ضروری نہ تھا کہ اس سے قتال کیا جاوے؟ اور پھر
طرفہ یہ کہ لڑائی کرنے سے پہلے حضرت خالد نے اپنا ایلچی طلیحہ کے پاس بھیجا.خونریزی
سے اس کو روکنا چاہا اور بہت سمجھایا مگر اس نے خالد کے پند و نصائح کو کسی طرح نہیں سنا.جب مسلمان عاجز آگئے اور کسی نصیحت نے بھی اثر نہ دکھایا تو ہار کے لڑائی کی ٹھہری.ابتدائے اسلام میں جن لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے قریب
دعوای نبوت کیا وہ صرف مسیلمہ اور طلیحہ ہی نہیں تھے بلکہ ان کے سوا اور بھی کئی اشخاص نے
Page 237
234
نبوت کا دعویٰ کیا.اور سب کی غرض دعوی نبوت سے صرف یہی تھی کہ حکومت حاصل ہو اور
ملک عرب کے کسی نہ کسی حصہ پر ان کو قبضہ حاصل ہو جائے.چنانچہ مدعیان نبوت میں سے
ایک اسود عنسی تھا اس نے مرتد ہوتے ہی علم بغاوت کھڑا کیا.اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کی طرف سے جو عاملین صدقات تھے ان کو صدقات واپس کرنے کا حکم دیا.عمال ابھی
تر ڈو میں تھے کہ قبائل مذحج و بخر ان کو لے کریمن کے مسلمان حاکم شہر بن باذان پر حملہ کر
کے اس کو قتل کر دیا اور اس کی جورو سے جبر انکاح کر کے سارے ملک یمن کا حاکم بن بیٹھا.اسود کی بغاوت کی خبر سُن کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وبر بن يُحنس کے ہاتھ حضرت
معاذ بن جبل اور اس کے ساتھی مسلمانوں کو خط بھیجا کہ اسود عنسی کا مقابلہ کرو.چنانچہ شہر بن
باذان کی بیوی کی مدد سے اسود عنسی کو اس کی خوابگاہ میں قتل کیا گیا.اور اس کے قتل کی خبر
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ایک دن اور ایک رات بعد مدینہ میں پہنچی.اسی طرح نبوت کا دعوی کرنے والوں میں سجاح بنت حارث بن سوید ایک
نصرانیہ عورت بھی تھی.وہ بھی دعوی نبوت کرتے ہی ایک بڑی فوج ساتھ لے کر مدینہ پر
چڑھ آئی.راستہ میں اس کو خبر ملی کہ مسیلمہ نے بھی نبوت کا دعوی کیا ہے اس لئے بعد مشورہ
یہ رائے ٹھہری کہ مدینہ پر حملہ کرنے سے پہلے مسیلمہ کا قلع قمع کرنا ضروری ہے.چنانچہ اس
نے یمامہ کی طرف رخ کیا.یہاں اس نے مسیلمہ سے اتحاد کر لیا.اور یہ تجویز ٹھہری کہ
مسیلمہ اور سجاح کی فوجوں کے ذریعہ کل عرب فتح کیا جائے.اس کے بعد خالد نے سجاح
کو شکست دی اور سجاح بھاگ کر جزیرہ میں بنی تغلب کے پاس جا چھپی.اسی طرح اہل عمان میں سے ایک شخص لقط بن مالک از دی نے مرتد ہو کر دعوای
نبوت کیا.اور نبوت کا دعوی کرتے ہی جمعیت اکٹھی کر کے علاقہ عمان پر حاکم ومتصرف
بن بیٹھا اور وہاں کے اصلی عمال جیفیر اور عبادکو نکال دیا.تاریخ طبری جلد ۴ صفحہ ۱۹۷۷.ابن خلدون جلد ۲ صفحہ ۷۸ و تاریخ الکامل جلد ۲ صفحه ۱۵۶)
Page 238
235
ان تمام واقعات سے ظاہر ہے کہ ان مدعیان نبوت کو نبوت سے کوئی غرض نہ تھی.ان کا منشاء صرف حکومت کا حاصل کرنا تھا.اس لئے یہ سب سلطنت کے باغی تھے اور ان کی
اس بغاوت کی وجہ سے ان کے ساتھ قتال کیا گیا.پس ان کی مثال سے ہرگز یہ ثابت نہیں
ہوتا کہ اسلام میں محض ارتداد کی سزا قتل ہے.مدعیان نبوت کے ساتھ بھی قتال کی وہی وجہ
تھی جو دوسرے مرتدین کے ساتھ قتال کرنے کی وجہ تھی یعنی ان سب نے اسلامی سلطنت
کے خلاف علم بغاوت بلند کیا.مسلمانوں
کو قتل کیا.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ
عمال کو اپنے اپنے علاقوں سے نکال کر خود حاکم اور متصرف بن بیٹھے اور مسلمانوں کے
خلاف جنگ کرنے کے لئے جمعیت اکٹھی کی اور بعض نے مدینہ پر چڑھائی بھی کر دی اور
مدینہ کا محاصرہ کیا.پس یہ وجوہات تھیں جن کی وجہ سے ضروری تھا کہ ان باغیوں سے قتال
کیا جاتا.لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر یہ مرتدین ان جرائم کے مرتکب نہ بھی ہوتے جو ان سے
ارتداد کے بعد سر زد ہوئے اور جن کی وجہ سے حفاظت اسلام کیلئے ان سے قتال کرنا واجب
ہو گیا اور ان کا جرم صرف اسی قدر ہوتا کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے زکوۃ دینے
سے انکار کرتے تو ان کا یہ اکیلا انکار اس بات کیلئے کافی تھا کہ ان سے قتال کیا جاتا اور اس
کی وجہ انہی الفاظ میں موجود ہے جو حضرت ابو بکر نے صحابہ کے مشورہ کے وقت فرمائے کہ
خدا کی قسم ! جب تک یہ تلوار میرے ہاتھ میں ہے میں منکرین زکوۃ کے ساتھ ایک عقال کی
کمی کے واسطے بھی جہاد کروں گا.جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ایک بکری
کا بچہ بھی بطور زکوۃ کے دیتے تھے اگر اب نہ دیں گے تو میں اس کے نہ دینے پر ان سے
جہاد کروں گا.اس قول کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کے صرف روحانی معنوں میں خلیفہ نہ تھے بلکہ وہ بادشاہت میں بھی آپ کے جانشین تھے.
Page 239
236
ملک عرب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سلطنت اسلامی قائم ہو چکی تھی اور آپ
کے جانشین کا یہ فرض اولین تھا کہ وہ اس سلطنت کا انتظام کریں.اور جو اموال سرکاری
خزانہ میں اس سلطنت کی رعایا کی طرف سے داخل ہوتے تھے ان کی وصولی کا انتظام
کریں.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں زکوۃ کی وصولی کا انتظام اسلامی حکومت
کے ماتحت تھا.اسلامی حکومت کی طرف سے اس کے وصول کرنے کے لئے عامل مقرر تھے
جو با قاعدہ اموال کی تشخیص کر کے زکوۃ اسی رنگ میں وصول کرتے جس طرح دوسری
حکومتیں اپنے اپنے محاصل وصول کرتی ہیں.یہ امر مومنین کی مرضی پر نہیں چھوڑا گیا تھا کہ جو
چاہیں دیں یا جس کو چاہیں دیں یا اگر اس میں غفلت کریں تو ان سے کوئی باز پرس کرنے
والا نہ ہو بلکہ یہ سارا انتظام حکومت کے ہاتھ میں تھا.حکومت کے آدمی زکوۃ کی تشخیص
کرتے اور وہی اس مال کو انتخاب کرتے جو انہوں نے زکوۃ کے طور پر لینا ہوتا تھا.محصلین
زکوۃ کو ہدایت تھی کہ وہ لوگوں کا بہترین مال زکوۃ کے لئے نہ لیں بلکہ درمیانی درجہ کا مال
لیں.مثلاً اگر کسی کے ذمہ ایک اونٹ نکلتا تو محصل کو ہدایت تھی کہ وہ ایسا نہ کرے کہ اس
شخص کے اونٹوں میں سے بہترین اونٹ چن کر لے بلکہ اس کو یہ ہدایت تھی کہ درمیانی درجہ
کا اونٹ انتخاب کرے.اس ہدایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس امر میں مال کے مالکوں کا
کوئی اختیار نہ تھا بلکہ تمام اختیار اس محصل کے ہاتھ میں تھا جو حکومت کی ہدایت کے ماتحت
کام کرتا تھا.پس اس میں ذرا بھی شک نہیں کہ زکوۃ کا مال رعایا سے اسی طرح وصول کیا
جاتا تھا جس طرح کہ دوسری گورنمنٹیں اپنی اپنی رعایا سے سرکاری مالیہ وصول کرتی ہیں یعنی
زکوۃ مسلمانوں پر ایک قسم کا ٹیکس تھا جو وہ حکومت اسلامی کو ادا کرتے تھے جس طرح کہ
دوسری قومیں اپنے اپنے بادشاہوں کو ٹیکس ادا کرتی ہیں.اور اس میں کچھ شک نہیں کہ یہی زکوۃ ہی وہ مال تھا جس کے ذریعہ سلطنت اسلامی
اس وقت کے اکثر اخراجات کو پورا کرتی.فوجی ضروریات اسی مال میں سے پوری کی
Page 240
237
جاتیں.اسلحہ جنگ.سپاہیوں کیلئے سواری اور دیگر سامان جنگ اسی زکوۃ کے مال سے مہیا
کیا جاتا.نیز سلطنت کا فرض ہوتا ہے کہ اپنی رعایا کی بہبودی کا ہر ایک رنگ میں خیال
رکھے.جولوگ بے روزگار ہیں یا کمانے کی طاقت نہیں رکھتے ان کی خبر گیری کرے.جو
لوگ کوئی فن جانتے ہیں مگر ان کے پاس سامان نہیں کہ وہ اس فن سے فائدہ اٹھا سکیں.سلطنت کا فرض ہے کہ ان لوگوں کی مدد کرے اور اس طرح اپنے ملک میں حرفت و صنعت و
تجارت کو ترقی دے.نیز سلطنت کا فرض ہے کہ جہاں سڑکوں اور سراؤں کی ضرورت ہے
وہاں مسافروں کی سہولت کے لئے سڑکیں تیار کرائے اور مسافروں کے آرام کے لئے
سرا ئیں بنوائے.دریاؤں اور ندیوں پر پل تیار کرائے.اور یہ سارے اخراجات اس قسم
کے ہیں کہ جن کے پورا کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے زکوۃ کا ٹیکس مسلمانوں پر لگایا ہے.اسی طرح بعض اوقات حکومت کو اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ اگر ان کی رعایا میں سے
کوئی فرد بعض مجبوریوں کی وجہ سے قرض کے بوجھ نیچے دب گیا ہے یا اس پر کوئی ایسا تاوان
پڑ گیا ہے جو اس کی طاقت سے بڑھ کر ہے تو ایسے شخص کی امداد کرے.اور یہ غرض بھی زکوۃ
کے مال سے ہی پوری ہوسکتی ہے.اسی طرح اسلامی سلطنت چونکہ محض ایک دنیوی سلطنت نہیں اس لئے اس کے
فرائض میں اشاعت اسلام بھی داخل ہے اور اس کا فرض ہے کہ وہ دین اسلام میں داخل
ہونے والوں کی مدد کرے اور ان کی تالیف قلب کے لئے مال خرچ کرے.اور یہ ضرورت
بھی زکوۃ کے مال سے ہی پوری ہو سکتی ہے.جو ضروریات میں نے اوپر بیان کی ہیں اور جو ہر ایک اسلامی سلطنت کو پیش آتی
ہیں یہ وہی مصارف ہیں جو اللہ تعالیٰ نے زکوۃ کے اموال کے لئے اپنی کتاب قرآن
شریف میں مقرر فرمائے ہیں.چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:.اِنَّمَا الصَّدَقْتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمُ
Page 241
238
وفِي الرِّقَابِ وَ الْعَرِمِينَ وَ فِى سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ
الله وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمُ (التوبة: 60)
صدقات تو صرف فقراء اور مساکین کے لئے ہیں اور ان کے لئے جو ان صدقات کے
جمع کرنے کے لئے مقرر کئے گئے ہیں.نیز ان کے لئے جن کے دلوں کو اپنے ساتھ
جوڑ نا مطلوب ہو اور اسی طرح قیدیوں اور قرض داروں کے لئے اور ان کے لئے جو اللہ
کے راستہ میں جنگ کرتے ہیں اور مسافروں کے لئے یہ فرض
اللہ کا مقرر کردہ ہے اور
اللہ بہت جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے.اس آیت کریمہ میں صدقات سے مراد ز کوۃ ہے اور اس کے مصرف وہی بیان کئے
گئے ہیں جو میں نے اوپر بیان کئے ہیں.اور یہ تمام مصارف ایسے ہیں جو ہر ایک اسلامی
سلطنت کا فرض ہے کہ وہ ان کا انتظام کرے.اور یہ تمام ضروریات ایسی ہیں جو ایک
اسلامی سلطنت کو پیش آتی ہیں.پس ہر ایک اسلامی سلطنت کا حق ہے کہ رعایا سے زکوۃ کا
مال مندرجہ بالا مصارف کے لئے وصول کرے.فریضہ زکوۃ اور فریضہ صلوۃ میں یہ فرق ہے کہ مؤخر الذکر کا تعلق صرف افراد سے
ہے اور اول الذکر کا تعلق محض افراد سے نہیں بلکہ حکومت کو بھی اس میں دخل ہے.اور اس کی
ادائیگی کا انتظام کرنا حکومت کے ذمہ ہے.بلکہ اس آیت کریمہ میں حکومت کے لئے یہ
ہدایت بھی دی گئی ہے کہ وہ اس کی وصولی کے لئے الگ محکمہ مقرر کرے اور اس محکمہ کے تمام
اخراجات اور کارکنوں کی تنخواہیں اور سفر خرچ وغیرہ زکوۃ کی مد سے ادا کئے جاویں.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم زکوۃ کی نسبت فرماتے ہیں:.تُؤْخَذُ مِنْ اَغْنِيَاءِ هِمْ وَتُرَدُّ إِلَى فُقَرَاءِ هِمُ.“
یعنی یہ ایک ٹیکس ہے جو دولتمندوں سے وصول کر کے فقراء پر خرچ کیا جاتا ہے.یہاں تُؤخذ اور تُردّ کے الفاظ بھی ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ حکومت کا فرض ہے کہ
Page 242
239
زکوۃ کا مال صاحب نصاب لوگوں سے لے کر فقراء کیلئے اور ان کے مصارف کے لئے جن
کی تفصیل قرآن شریف میں بیان کی گئی ہے خرچ کرے.اللہ تعالیٰ نے خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ
دَقَةٌ کہہ کر نہ صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بلکہ آپ کے جانشینوں اور اسلامی
حکومتوں کے امراء کوحکم دیا ہے کہ وہ زکوۃ کا مال وصول کریں.چنانچہ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے اس کی وصولی کا انتظام اپنے ہاتھ میں لیا.اور تمام علاقوں میں اپنی طرف سے
عامل مقرر کئے.جن کا یہ فرض تھا کہ وہ زکوۃ کے مال کو وصول کریں اور آپ کے زمانہ میں
زکوۃ ٹھیک اسی طرح وصول کی جاتی تھی جس طرح آج کل تمام حکومتیں اپنی اپنی رعایا سے
مختلف قسم کے ٹیکس اور محاصل وصول کرتی ہیں.اور چونکہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ آپ کے
جانشین تھے اس لئے ان کا بھی یہ فرض تھا کہ وہ ٹھیک اسی طرح زکوۃ کا مال مسلمانوں سے
وصول کریں جس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم وصول فرمایا کرتے تھے.اسی لئے حضرت
ابو بکر نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوزکوۃ میں ایک عقال بھی دیا
کرتا تھا اور اب دینے سے انکار کرے گا تو میں تلوار کے زور سے اس سے وصول کروں گا.پس اس کی وصولی اسی طرح تھی جس طرح کہ حکومتیں اپنی اپنی رعایا سے اپنے محاصل وصول
کرتی ہیں.اور اگر کوئی رعایا میں سے ایسے محاصل کو ادا کرنے سے انکار کرے تو سلطنت
اپنی تلوار کے زور سے ان محاصل کو وصول کرتی ہے.حضرت ابوبکر کے وقت میں جن
مسلمانوں نے زکوۃ دینے سے انکار کیا ان کی ایسی ہی مثال ہے جیسا کہ کوئی شخص رعایا میں
سے سرکاری مالیہ ادا کرنے سے انکار کرے.اور حضرت ابوبکر کا فرض تھا کہ وہ تلوار کے
زور سے ایسے لوگوں سے زکوۃ وصول فرماتے.وہ لوگ ایسے ہی باغی تھے جیسا کہ وہ لوگ
سلطنت کے باغی سمجھے جاتے ہیں جو اپنی حکومت کو سرکاری ٹیکس ادا کرنے سے انکار کرتے
ہیں.پس اگر حضرت ابو بکر نے ایسے مسلمانوں سے قتال کیا جن کا سوائے اس کے اور کوئی
جرم نہ تھا کہ انہوں نے زکوۃ دینے سے انکار کیا تو اس سے ہمارے مخالفوں کو کوئی فائدہ نہیں
Page 243
240
پہنچتا.کیونکہ حضرت ابو بکر کا قتال ایسے لوگوں کے خلاف تھا جو سلطنت سے باغی تھے.یہ درست ہے کہ بعض صحابہ نے خصوصاً حضرت عمرؓ نے مشورہ کے وقت حضرت
ابوبکر کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ کس طرح ایسے لوگوں سے جہاد کر سکتے ہیں جو لا الله
الا اللہ کہنے والے ہیں کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں سے کبھی جہاد نہیں
کیا.مگر حضرت
عمر کا یہ سوال ایسا ہی تھا جیسا کہ حضرت ابوبکڑ نے ایک دوسرے موقع پر خود
حضرت عمرؓ سے سوال کیا.جب حضرت عمرؓ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یمامہ کی
لڑائی میں بہت سے قاری شہید ہو گئے ہیں.اور اگر اسی طرح کی اور لڑائیاں پیش آئیں تو
خوف ہے کہ قرآن کے حفاظ کے شہید ہو جانے سے قرآن شریف کے بعض حصے معدوم نہ
ہو جاویں.اس لئے ضروری ہے کہ اس وقت قرآن شریف کی حفاظت کا کوئی انتظام کیا
جاوے اور اس کو ایک جگہ لکھ کر محفوظ کر لیا جاوے.اس وقت حضرت ابو بکڑ نے بھی حضرت
عمرؓ سے ایسا ہی سوال کیا جیسا کہ حضرت عمرؓ نے حضرت ابوبکر سے مانعین زکوۃ کے سوال
کے موقع پر کیا.حضرت ابو بکر نے حضرت عمرؓ سے کہا کہ میں کس طرح ایسا کام کر سکتا ہوں
جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ؟ پس یہ دونوں سوال ایک ہی رنگ کے ہیں اور
ان کا ایک ہی جواب ہے اور وہ یہ ہے کہ ہر ایک کام کا ایک وقت ہوتا ہے.آنحضرت صلی
اللہ علیہ وسلم کو ایسے دشمنوں سے واسطہ پڑا جو مسلمانوں کو امن سے زندگی بسر کرنے نہیں
دیتے تھے.وہ مسلمانوں کو دکھ دیتے تھے اور چاہتے تھے کہ تلوار کے ساتھ اسلام کا نام و
نشان مٹادیں.آپ نے ایسے دشمنوں کا مقابلہ کیا اور ملک میں امن و امان قائم کر کے ایک
اسلامی سلطنت کی بنیاد ڈالی اور شرائع اسلام کو نافذ کیا.اور دوسری شرائع کے درمیان آپ
نے زکوۃ کا فریضہ بھی تمام اہل نصاب پر قائم کیا اور اس کی وصولی کا انتظام کیا.آپ کے
وقت میں کوئی ایسی مسلمان کہلانے والی قوم نہ اٹھی جو فریضہ زکوۃ کے ادا کرنے سے انکار
کرے.اس لئے آپ کو کسی ایسی قوم سے قتال کی ضرورت ہی پیش نہ آئی.یہ ضرورت
Page 244
241
پہلی دفعہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو پیش آئی.جو مال کا حق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
مسلمانوں پر مقرر کیا اور جس کی وصولی کا انتظام آپ نے اپنے ہاتھ میں لیا تھا اور جس کو وہ
حکومت اسلامی کے بیت المال میں داخل فرما کر حکومت کی ضروریات کے لئے خرچ
فرماتے تھے.آپ کی وفات پر آپ کے جانشین کو ان محاصل کے دینے سے انکار کیا گیا.اس لئے اس کا فرض تھا کہ وہ اپنی حکومت کے زور سے سلطنت اسلامی کی رعایا سے ان
محاصل کو وصول کرتا.اور اگر اس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے وہ بھی کبھی
اس امر کی اجازت نہ دیتے کہ لوگ آپ کے عمال کو زکوۃ کا مال ادا نہ کریں.علاوہ ازیں حکومت کا ایک کام احتساب بھی ہے یعنی جو لوگ اسلام میں داخل ہو کر
شرائع اسلام کی پابندی سے کنارہ کشی اختیار کر میں حکومت اسلامی کا فرض ہے کہ ان کے
خلاف تحذیری تدابیر عمل میں لائے اور ان کو احکام شریعت کی خلاف ورزی سے رو کے.پس احتسابی پہلو سے بھی حضرت ابوبکر کا فرض تھا کہ جو لوگ اپنے تئیں مسلمان کہلاتے
تھے اور زکوۃ دینے سے جو اسلام کے ارکان میں داخل ہے انکار کرتے تھے ان کو مجبور کرتے
کہ وہ اسلام کے اس فریضہ کو ادا کریں.اس جگہ یہ کہنا درست نہ ہوگا کہ امیر کا بل نے بھی احمد مکی جماعت کے افراد کو احتساباً
قتل کیا ہے کیونکہ احمدی جماعت نے ارکان اسلام میں سے کسی رکن کا انکار نہیں کیا اور نہ
کسی شرعی حکم کی خلاف ورزی کی اور نہ ان کو مسلمان
سمجھ کر سزا دی گئی.بلکہ ان کو اسلام سے
خارج قرار دے کر قتل مرتد کے فرضی حکم کے ماتحت سنگسار کیا.اس لئے یہ عذر یہاں
درست نہیں ہوسکتا کہ ان کے خلاف احتسا با ایسی کارروائی کی گئی.خلاصہ کلام یہ ہے کہ تاریخ سے اول تو کسی ایسی قوم کا پتہ نہیں چلتا جنہوں نے
صرف منع زکوۃ پر اکتفا کیا ہو بلکہ جہاں تک تاریخ سے پتہ چلتا ہے جن جن قوموں کے
خلاف حضرت ابو بکر نے فوج کشی کا حکم دیا وہ سب کے سب کھلم کھلا سلطنت اسلام سے
Page 245
242
باغی ہو گئے تھے.انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عمال کو اپنے اپنے علاقہ سے
نکال دیا.جولوگ ان میں سے اسلام پر قائم رہے ان
کو قتل کیا.بعض نے مدینہ پر چڑھائی
کی اور سب اپنے اپنے علاقہ پر متصرف ہو کر اور فوجیں جمع کر کے مسلمانوں کے ساتھ
جنگ کرنے کے لئے تیار ہو گئے.اس لئے اسلام اور حکومت اسلام کی حفاظت کے لئے
ان کا مقابلہ کرنا ایسا ہی ضروری ہو گیا تھا جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں
مشرکین سے جنگ کرنا ضروری ہو گیا تھا.اور اگر کوئی قبیلے ایسے بھی تھے جن کا جرم صرف منع
زکوۃ تک محدود تھا اور وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے تھے تو ان کے ساتھ بھی قتال ضروری
تھا.کیونکہ ان کی مثال ایسی ہی تھی جیسے ایک حکومت کی رعایا اپنی حکومت کو سرکاری مالیہ ادا
کرنے سے انکار کر دے.اس لئے ضروری تھا کہ تلوار کے زور سے ان سے زکوۃ وصول
کی جاوے.علاوہ ازیں احتساباً بھی حکومت اسلامیہ کا فرض تھا کہ جو لوگ اپنے آپ کو
مسلمان کہتے تھے مگر زکوۃ کے ادا کرنے سے انکار کرتے تھے ان کے خلاف تحذیری
کارروائی کرے اور ان کو شرائع اسلام کی پابندی پر مجبور کرے.اب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے عہد کے متعلق صرف ایک بات باقی رہ جاتی ہے
جس کا جواب دے کر میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے عہد کو ختم کرتا ہوں.قتل مرتد کے
دعویداروں نے اپنے دعوی کی تائید میں یہ بات بھی پیش کی ہے کہ حضرت ابوبکر نے ایک
مرتد ہ امتم قرفہ کو قتل کیا.مگر حامیان قتل مرتد یہ سن کر مایوس ہوں گے کہ یہاں بھی خالی ارتداد کا سوال نہ
تھا.اور اس کے قتل کی یہ وجہ نہ تھی کہ وہ مرتد ہو گئی تھی بلکہ اس کے قتل کی یہ وجہ تھی کہ وہ ایک
محاربہ عورت تھی جو لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کے لئے اکساتی تھی اور مسلمانوں
کے خلاف جنگ کی آگ بھڑکاتی تھی.چنانچہ مبسوط جلد 10 صفحہ 110 پر لکھا ہے:.وام قرفة كان لها ثلاثون ابناء وكانت تحرضهم على قتال
Page 246
"
243
المسلمين و في قتلها كسر شوكتهم.یعنی ام قرفہ کے تمہیں بیٹے تھے اور وہ ان کو مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کے
لئے ابھارتی تھی.اور اس کے قتل میں یہ فائدہ تھا کہ اس طرح اس کے بیٹوں کی شوکت
ٹوٹ جاتی تھی.پس ام قرہ کا قتل بھی اس کے ارتداد کی وجہ سے نہ تھا بلکہ اس لئے تھا کہ وہ
محاربہ تھی اس لئے اس کا قتل تعلیم قرآن کے عین مطابق تھا.حضرت ابوبکر کے جنگوں کی طرح حضرت علی کے وقت کے بعض جنگوں سے بھی قتل
مرتد کے دعویداروں نے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے چنانچہ یہ کہا گیا ہے کہ
حضرت علیؓ نے خارجیوں
کو قتل کیا جو مرتد تھے.اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام میں
ارتداد کی سزا قتل ہے.لیکن حامیان
قتل مرتد کے لئے یہ افسوس کا مقام ہے کہ یہاں بھی ان
کی غرض پوری نہیں ہوتی.کیونکہ یہ ایک ثابت شدہ تاریخی واقعہ ہے کہ خارجیوں سے جو
لڑائی ہوئی وہ بھی بغاوت اور فتنہ کو فرو کرنے کے لئے تھی نہ کہ محض چند مسائل کے اختلاف
کی وجہ سے.جیسا کہ مندرجہ ذیل واقعات سے ظاہر ہے:.(۱) حضرت علی نے ان سے گفتگو کرتے وقت فرمایا." فقال لهم لكم علينا ثلاثة ان لا نمنعكم من المساجد ولا من
رزقكم من الفئ ولا نبدءكم بقتال مالم تحدثوا فسادا فخرجوا
شيئًا بعد شئ الى ان اجتمعوا بالمدائن فراسلهم في الرجوع
فاصروا على الامتناع حتى يشهد نفسه بالكفر لرضاه بالتحكيم
ويتوب ثم راسلهم ايضا فأرادوا قتل رسوله ثم اجتمعوا على ان من
لا يعتقد معتقدهم يكفر ويباح دمه وماله واهله وانتقلوا الى الفعل
فاستعرضوا الناس فقتلوا من اجتاز بهم من المسلمين ومرعليهم
عبدالله بن
بن خباب الارت وكان واليا لعلى على بعض تلك البلاد و
Page 247
244
معه سريته وهي حامل فقتلوه وبقروا بطن سريته عن ولد فبلغ عليّا
فخرج اليهم في الجيش الذي كان هياه للخروج فاوقع بهم
بالنهروان.“
(فتح الباری جلد 12 صفحہ 251)
یعنی حضرت علیؓ نے ان سے کہا تھا کہ ہم تین باتیں اپنے ذمہ لیتے ہیں.اول یہ کہ ہم تم
کو مسجدوں سے نہیں روکیں گے.غنیمت کے مال سے تم کو حصہ دیں گے اور تمہارے
ساتھ جنگ کی ابتدا نہ کریں گے جب تک کہ تم خود فساد نہ کھڑا کرو.اس کے بعد وہ
آہستہ آہستہ وہاں سے نکل گئے اور انہوں نے مدائن میں اجتماع کیا.وہاں حضرت علیؓ
نے اُن کو پیغام بھیجا کہ وہ واپس آجاویں مگر انہوں نے انکار کیا اور کہا کہ ہم واپس نہیں
آئیں گے جب تک کہ تم اپنے متعلق یہ گواہی نہ دو کہ میں تحکیم پر راضی ہو جانے کی وجہ
سے کافر ہو گیا اور پھر تو بہ نہ کرو.حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دوبارہ پیغام بھیجا.اس دفعہ
انہوں نے چاہا کہ آپ کے ایلچی کوقتل کر دیں پھر انہوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ جو
شخص ان کے عقیدے کو قبول نہیں کرتا وہ کافر ہے اور اس کا خون بہانا اور اس کا مال
لوٹ لینا اور اس کے گھر والوں کو قتل کر دینا مباح ہے.اور انہوں نے یہ فیصلہ ہی نہ کیا
بلکہ اس پر عملدرآمد بھی شروع کر دیا.وہ لوگوں کو روک لیتے اور جو لوگ ان کے پاس
سے گزرتے ان کو قتل کر دیتے.ان کے پاس سے اتفاقاً عبداللہ بن حباب کا گزر
ہو اور وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے ان ممالک میں سے بعض پر حاکم مقرر تھے
اور ان کے ساتھ ان کی لونڈی تھی جو حاملہ تھی.انہوں نے حضرت عبداللہ بن خباب کو
قتل کر دیا اور ان کی لونڈی کا پیٹ چیر کر اس کا بچہ نکال دیا.جب یہ خبر حضرت علی رضی
اللہ عنہ کو پہنچی تو وہ لشکر لے کر ان کی طرف نکلے اور نہروان کے مقام پر اُن پر حملہ کیا.مندرجہ بالا واقعات سے جو سب تاریخ کی کتابوں میں درج ہیں صاف ظاہر ہے
Page 248
245
کہ حضرت علیؓ نے خوارج کے ساتھ ان کے عقائد کی وجہ سے لڑائی نہیں کی بلکہ ان کی
بغاوت اور فساد کی وجہ سے ان سے لڑائی کی.(۲) تاریخ الکامل اور دوسری کتب تاریخ میں لکھا ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو
عبداللہ بن خباب کے قتل کی خبر پہنچی اور نیز یہ کہ وہ لوگوں کو روک لیتے ہیں.تو حضرت علی
نے اس امر کی تحقیق کے لئے الحرث بن مرۃ العبدی کو بھیجا.اور جب وہ ان کے پاس اس
امر کے دریافت کرنے کے لئے آیا تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس ایلچی کو قتل
کر دیا.چنانچہ تاریخ الکامل جلد ۳ صفحہ ۱۴۸ پر لکھا ہے.فاضجعوه ای عبدالله بن خبّاب) فذبحوه فسال دمه في الماء
واقبلوا الى المرأة فقالت انا امرأة الا تتقون.فبقروا بطنها وقتلوا
ثلاث نسوة من طئ وقتل ام سنان الصيدادية.فلما بلغ عليا قتلهم
عبدالله بن خبّاب واعتراضهم الناس بعث اليهم الحرث بن مرة
العبدى ليأتيهم وينظر ما بلغه عنهم ويكتب به اليه ولا يكتم منهم
66
فلما دنا منهم يسألهم قتلوه “
یعنی خارجیوں نے عبد اللہ بن خباب کو لٹایا اور اس کو ذبح کیا.اور اس کا خون بہہ کر پانی
میں مل گیا.پھر وہ اس عورت کی طرف متوجہ ہوئے.اس نے کہا کہ میں تو ایک عورت
ہوں کیا تم خدا تعالیٰ سے نہیں ڈرتے ؟ انہوں نے اس کا پیٹ چیر دیا.اور بنی طئی کی تین
عور تیں قتل کر دیں اور ام سنان الصداد یہ کو قتل کر دیا.جب حضرت
علی کو یہ خبر پہنچی کہ
انہوں نے عبداللہ بن خباب
کو قتل کر دیا ہے اور یہ کہ وہ لوگوں کو راستہ میں روک لیتے ہیں
اور ان
کو قتل کر دیتے ہیں تو انہوں نے الحرث بن مرۃ العبدی کو بھیجا.کہ وہ ان کے پاس
جائیں اور دیکھیں جو خبریں اُن کو پہنچتی ہیں وہ کہاں تک درست ہیں اور ان کو صحیح صحیح
حالات لکھ کر بھیجیں.جب الحرث بن مرة العبدی ان سے پوچھنے کے لئے ان کے
Page 249
246
قریب ہوئے تو انہوں نے اس
کو قتل کر دیا.(۳) حضرت علی رضی اللہ عنہ فوج لے کر اس مقام پر پہنچے تو انہوں نے جاتے ہی
حملہ نہیں کر دیا بلکہ حملہ کرنے سے پہلے ان کو کہلا بھیجا کہ تم ان لوگوں کو ہمارے حوالہ کر دو
جنہوں نے ہمارے آدمیوں
کو قتل کیا ہے تا ہم ان
کو قتل کر دیں.ہم دوسروں سے فی الحال
درگزر کرتے ہیں اور ان کی مہلت دیتے ہیں تا شاید ان کے خیالات میں تبدیلی پیدا ہو
جائے اور ان کی حالت سدھر جائے.مگر انہوں نے جواب دیا کـلـنــا قـتـلـهـم وكـلنـا
مستحل لدماء كم و دمائهم یعنی ہم سب نے ان کو قتل کیا اور ہم سب تمہارے خونوں
کا اور ان کے خونوں کا بہانا جائز سمجھتے ہیں.مندرجہ بالا حوالجات سے ظاہر ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کسی مذہبی اختلاف کی
وجہ سے خوارج سے لڑائی نہیں کی بلکہ اس لئے کہ انہوں نے ملک میں فتنہ وفساد برپا کر دیا اور
مسلمان مردوں اور عورتوں کو قتل کر دیا.اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقرر کردہ
والی اور اس کی لونڈی کو قتل کر دیا اور نیز آپ کے ایچی کو قتل کیا.اور جب حضرت علی نے ان
سے مطالبہ کیا کہ جن آدمیوں کو تم نے قتل کیا ہے ان کے قاتل میرے حوالہ کر دو.تو انہوں
نے جواب دیا ہم سب ان کے قاتل ہیں اور ہم نہ صرف ان کا خون بہانا جائز سمجھتے ہیں بلکہ
تمہارا خون بہانا بھی جائز سمجھتے ہیں.علاوہ ازیں خوارج کی مثال حامیان
قتل مرتد کے لئے اس وجہ سے بھی مفید نہیں کہ اکثر
علماء کا اتفاق ہے کہ خارجی لوگ مرتد نہیں بلکہ فرقة من فرق المسلمین کا حکم رکھتے ہیں.فتح الباری جلد 12 صفحہ 247 میں لکھا ہے:.قال الخطابي اجمع علماء الاسلام على ان الخوارج مع ضلالتهم
فرقة من فرق المسلمين واجازوا مناكحتهم واكل ذبائحم وانهم
لا يكفرون ما داموا متمسکین باصل الاسلام.“
Page 250
247
یعنی خطابی کہتا ہے کہ علماء اسلام نے اتفاق کیا ہے کہ خارج باوجود اپنی گمراہی کے
مسلمان فرقوں میں سے ایک فرقہ ہیں اور ان کے ساتھ مناکحت جائز ہے اور جب تک
وہ اصل اسلام پر قائم ہیں وہ کا فرنہیں کہلائے جاسکتے.پھر اسی کتاب کے صفحہ 268 پر لکھا ہے:.قال ابن بطل ذهب جمهور العلماء الى ان الخوارج غير خارجين
من جملة المسلمين.“
یعنی ابن بطل نے کہا ہے کہ جمہور علماء کا یہ مذہب ہے کہ خوارج مسلمانوں کی جماعت
سے خارج نہیں.تفسیر کبیر جلد 3 کے صفحہ 614 پرلکھا ہے:.ان اسم المرتد انّما يتناول من كان تاركا للشرائع الاسلامية
والقوم الذين نازعوا عليّا ماكانوا كذلك في الظاهر وماكان احد
يقول انه انما يحاربهم لاجل انهم خرجوا من الاسلام وعلى لم
يسمهم البتة بالمرتدين.“
یعنی مرتد کا نام اس شخص پر اطلاق پاتا ہے جو شرائع اسلامی کو ترک کر دے.اور جس قوم
نے حضرت
علی کی مخالفت کی وہ ظاہر میں شرائع اسلامی کے تارک نہ تھے.اور کوئی شخص
یہ نہیں کہتا تھا کہ حضرت علی اس لئے ان سے جنگ کرتے ہیں کہ وہ اسلام سے خارج ہو
گئے ہیں اور حضرت علی نے ہرگز ان کا نام مرتد نہیں رکھا.منهاج السنة مصنفہ شیخ ابن تیمیہ جلد 3 کے صفحہ 62،61 پر لکھا ہے:.قال الاشعرى وغيره اجمعت الخوارج على تكفير على ابن ابی
طالب....ومع هذا فقد صرح على بأنهم مؤمنون ليسوا كفارا ولا
منافقين ومما يدلّ على ان الصحابة لم يكفروا الخوارج
Page 251
248
انهم كانوا يصلون خلفهم وكان عبدالله بن عمرو غيره من
الصحابة كانوا يصلون خلف نجدة الحرورى وكانوا أيضا
يحدثونهم ويفتونهم ويخاطبونهـم كـمـا يخاطب المسلم
المسلم....وما زالت سيرة المسلمين على هذا ما جعلوهم
مرتدين كالذين قاتلهم الصديق رضي الله عنه....ومع هذا
فالصحابة والتابعون لهم باحسان لم يكفروا هم ولا جعلوهم
مرتدين ولا اعتدوا عليهم بقول ولا فعل بل اتقوا الله فيهم وساروا
فيهم سيرة العادلة.یعنی اشعری وغیرہ نے کہا کہ حضرت علی کی تکفیر پر تمام خوارج کا اجتماع ہے.مگر باوجود
اس کے حضرت علیؓ نے بالصراحت بیان کیا ہے کہ وہ مومن ہیں کا فرنہیں اور نہ منافق
ہیں...اور اس بات کی ایک دلیل کہ صحابہ خوارج کو کافر نہیں کہتے تھے یہ ہے کہ وہ
خوارج کے پیچھے نماز پڑھ لیتے تھے اور حضرت عبداللہ بن عمر اور دوسرے صحابہ
نجدة الحروری کے پیچھے نماز پڑھ لیا کرتے تھے اور نیز ان کو احادیث سناتے تھے اور ان کو
فتوی دیتے تھے اور ان سے اسی طرح خطاب کرتے تھے جس طرح ایک مسلمان
ے مسلمان سے مخاطب ہوتا ہے....اور مسلمان ان سے ہمیشہ ایسا ہی معاملہ کرتے
رہے ہیں انہوں نے ان مرتدین کی طرح ان
کو نہیں سمجھا جن سے حضرت صدیق نے
قبال کیا...صحابہ اور تابعین نے ان کو کافر قرار نہیں دیا اور نہ ان کو مرتد ٹھہرایا اور نہ ان
پر زبان سے یا ہاتھ سے کسی طرح کی زیادتی کی بلکہ ان کے بارے میں تقوی سے کام
لیتے رہے اور ان کے ساتھ عدل کا معاملہ کیا.دوسرے
اس تمام بحث سے یہ امر بپایہ ثبوت پہنچ جاتا ہے کہ قتل مرتد کے دعویداروں کا
خوارج کے واقعہ سے اپنے دعوای کی تائید میں استدلال کرنا ایسا ہی باطل ہے جیسا کہ ان
Page 252
249
کے دوسرے تمام استدلات باطل ہیں.خوارج کو نہ حضرت علیؓ نے مرتد قرار دیا اور نہ
دوسرے صحابہ نے.اور حضرت علی نے ان کے اعتقادات کی وجہ سے ان کیساتھ لڑائی نہیں
کی بلکہ ان کی خونریزی کی وجہ سے.دوسرا واقعہ جو قتل مرتد کی تائید میں پیش کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت
علی نے بعض
زنادقہ کو جو ان کو خدا کہتے تھے آگ میں ڈال کر جلایا اور اس کی تائید میں مندرجہ ذیل
روایت پیش کی جاتی ہے.عن عكرمة قال اتى على زنادقة فاحرقهم يعنى
حضرت علی زنادقہ کے پاس گئے اور ان کو آگ میں ڈال کر جلا دیا.اس روایت کی بناء
عکرمہ کے بیان پر ہے جو حضرت ابن عباس کے آزاد کردہ غلام تھے اور اس میں حضرت علیؓ
پر یہ الزام لگایا گیا ہے کہ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کے خلاف کہ
لا تعذبوا بعذاب الله یعنی جس چیز کے ساتھ اللہ تعالیٰ عذاب دیتا ہے اس کے ساتھ تم
کسی کو عذاب نہ دو.بعض آدمیوں کو اس لئے آگ میں ڈال کر جلا دیا کہ وہ ان کو خدا مانتے
تھے.چنانچہ اسی روایت میں عکرمہ بیان کرتا ہے کہ جب یہ خبر حضرت ابن عباس کو پہنچی تو
انہوں نے کہا کہ اگر میں ہوتا تو ان لوگوں کو ہرگز نہ جلا تا کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے منع فرمایا ہے کہ کسی کو آگ کے ساتھ عذاب دیا جاوے.پس اگر اس روایت کو درست
مانا جاوے تو ماننا پڑتا ہے کہ حضرت علیؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نعوذ باللہ
خلاف ورزی کی اور یہ امر ہم کبھی بھی حضرت
علی جیسے انسان کے لئے ایک لمحہ کے لئے بھی
تسلیم نہیں کر سکتے.حضرت
علی بچپن سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے.اس
وقت حضرت ابن عباس پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جبکہ حضرت
علی کو اللہ تعالیٰ نے شرف قبول
اسلام بخشا اور آپ نے خود حضرت علی کی پرورش اور تربیت فرمائی.اور جو قرب حضرت علی
کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاصل رہا وہ کبھی حضرت ابن عباس کو حاصل نہیں
ہوا.پس ہم اس بات کو ہر گز قبول نہیں کر سکتے کہ حضرت علی محضرت ابن عباس سے اپنے علم
Page 253
250
میں کم تھے.صحیح بخاری کی ایک روایت کے مطابق حضرت ابن عباس آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کی وفات کے وقت صرف دس سال کے تھے.حضرت علی وہ ہیں جن کی نسبت
بیان کیا گیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انـا مـديـنـة العلم و على بابها
پس حضرت علی کی نسبت یہ خیال کرنا کہ ان کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد
لا تـعـذبـوا بعذاب اللہ کا علم نہ تھا اور انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی
صریح خلاف ورزی میں کئی آدمیوں کو آگ میں جلا دیا ایک خیال باطل ہے.یہ تاریخ سے ثابت ہے کہ حضرت علی کو بدنام کرنے کے لئے مختلف قسم کے الزام
ان پر لگائے گئے اور یہ بھی انہی الزامات میں سے ایک الزام ہے اور ہر ایک مومن کا فرض
ہے کہ حضرت
علی پر نیک فن کر کے ایسے الزامات سے ان کو پاک ٹھہرائے اور جو شخص اس
روایت کا بانی ہے اس کے حالات اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ یہ روایت ایک انتہام ہے
جو حضرت
علی پر لگایا گیا.میزان الاعتدال میں اس کی نسبت لکھا ہے کہ عکرمہ کے بارے
میں حافظہ کی وجہ سے نہیں بلکہ خوارج کی رائے اختیار کرنے کی وجہ سے کلام ہے.سعید بن
جبیر اگر چہ اسے اپنے سے اعلم بتاتے ہیں مگر ساتھ ہی ابن مسیب اس کو کذاب بھی کہتے
ہیں.عبداللہ بن الحارث کہتا ہے کہ میں علی بن عبد اللہ بن عباس کے پاس گیا.کیا دیکھتا
ہوں کہ عکرمہ باب الحش کے پاس باندھا ہوا تھا.میں نے کہا کہ میاں
اللہ تعالیٰ سے
ڈرو.کہنے لگے کہ یہ خبیث میرے باپ پر افترا کرتا ہے.حماد بن زید جب مرنے لگے تو
فرمایا کہ عذاب الہی سے ڈر کر کہتا ہوں کہ عکرمہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے متشابہات اس لئے
اتاری ہیں کہ ان کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرے.محمد بن سیرین اس کو کذاب کہتا ہے.عکرمہ جب بصرہ میں آیا تو اس کے پاس یونس اور ایوب اور سلیمان التیمی ملنے کے لئے
آئے.اندر سے گانے کی آواز آرہی تھی.سن کر کہا کہ ملعون کیا ہی خوب گا تا ہے.پھر
یونس اور سلیمان اس کے پاس کبھی نہیں آئے.ابن المدینی کہتے ہیں کہ عکرمہ ایک مسجد کے
Page 254
251
دروازہ پر کھڑا ہو کر کہتا تھا کہ اس میں سب کافر ہیں.اباحت کی رائے رکھتا تھا.یحیی بن
بکر کہتا ہے کہ مغرب میں خارجی عکرمہ کی وجہ سے پیدا ہوئے.ابن المدینی کہتا ہے کہ عکرمہ
کی رائے نجدہ حروری سے ملتی تھی.مصعب الزبیری کہتے ہیں کہ مکرمہ خوارج کی رائے رکھتا
ہے.متولی مدینہ نے اس کو طلب کیا مگر وہ داؤد بن حصین کے گھر چھپا رہا.مرنے تک نہ نکلا
اور انہوں نے کہا کہ عکرمہ نے یہ بھی دعوی کیا کہ حضرت ابن عباس خوارج کی رائے رکھتے
تھے.سلیمان بن معبد کہتے ہیں کہ عکرمہ اور کثیر ایک ہی دن مرے مگر لوگوں نے کثیر کا جنازہ
پڑھا.عکرمہ کا جنازہ نہ پڑھا.ناظرین غور فرماویں کہ اس حدیث کے راوی عکرمہ کی نسبت کس کثرت سے یہ
شہادت دی گئی ہے کہ وہ خوارج کی رائے رکھتا تھا بلکہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ مغرب میں
خوارج اُسی کی وجہ سے پیدا ہوئے اور یہ کہ حضرت ابن عباس پر بھی افتر ا کرنے سے باز
نہیں رہتا تھا اور ان کی نسبت بھی یہی ظاہر کرتا تھا کہ وہ خوارج کی رائے رکھتے تھے.پس
ایسے شخص کی روایت حضرت علیؓ کے خلاف کس طرح صحیح تسلیم کر سکتے ہیں؟ روایت کو غور
سے پڑھو اس سے صاف راوی کا یہ منشاء معلوم ہوتا ہے کہ وہ حضرت علی پر اس امر کا الزام لگائے
کہ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بعض لوگوں کو
آگ میں جلایا.کیونکہ وہ اپنی روایت میں بیان کرتا ہے کہ جب یہ خبر حضرت ابن عباس رضی اللہ
عنہ نے سنی تو انہوں نے فرمایا کہ اگر میں ہوتا تو ان لوگوں کو آگ میں نہ جلاتا.کیونکہ ایسا فعل
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہے.آپ نے فرمایا "لا تعذبوا بعذاب الله.»
پس ہم عکرمہ جیسے راوی کی بناء پر حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسے مقدس انسان پر یہ
الزام نہیں لگا سکتے کہ آپ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی خلاف ورزی کی اور
ایک ایسا کام کیا جو شریعت کی حد سے خارج ہے اور یہ ایسا فعل ہے کہ خواہ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کا اس کے خلاف ارشاد نہ بھی ہوتا.تب بھی خود علی رضی اللہ عنہ ایسی پاکیزہ فطرت
Page 255
252
کے انسان تھے کہ ان کی اپنی فطرت طبعی طور پر ایسے فعل کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتی جو ان کے
آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو نا پسند تھا.ان زنادقہ کی مثال ایک اور پہلو سے بھی قتل مرتد کے حامیوں کے لئے مفید نہیں.کیونکہ تاریخ سے ثابت ہے کہ ان لوگوں کو دراصل حضرت علی کو خدا بنانے سے کوئی غرض نہ
تھی بلکہ اس کا اصل منشاء مسلمانوں کی جماعت میں تفرقہ ڈالنا تھا.اس پارٹی کا سرغنہ عبداللہ
بن سباء الحمیر ی یہودی تھا.عبد اللہ بن سباء اور اس کے ساتھیوں کا مختصر حال میں تاریخ کی
کتابوں سے ذیل میں نقل کرتا ہوں.تا ناظرین کو معلوم ہو کہ یہ کیسے خطر ناک لوگ تھے.ابن حزم کی مشہور تصنيف الـفـصـل فـي الـمـلـل والاهواء والنحل کی جلد
2 صفحہ 115 پر لکھا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر جو حملہ کیا گیا اور ان کو شہید کیا گیا اس
حملہ کا بانی مبانی یہی ملعون ابن سباء تھا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خدا کہنے والے اسی کے
اتباع تھے.اس کی نسبت کتاب مذکور کا فاضل مصنف لکھتا ہے فـانــه لـعـنـه اللـه أظهر
الاسلام لكيد أهله یعنی اس ملعون نے اپنے تئیں مسلمان ظاہر کیا اور اس کی نیت یہ تھی
کہ مسلمانوں میں فتنہ و فساد پیدا کرے.الملل والنحل شارستانی برحاشیہ الفصل لا بن حزم
کی جلد 2 صفحہ 11 پر لکھا ہے کہ ابن سباء نے حضرت علی کو کہا انت انت يعني أنت الاله
یعنی تو ہی خدا ہے.اس پر حضرت علیؓ نے اس کو مدائن کی طرف جلا وطن کر دیا.تاریخ طبری
جلد 6 صفحہ 3191 پر لکھا ہے کہ واقعہ جمل کے وقت حضرت عائشہ نے صلح کے لئے کعب کو
قرآن شریف دے کر حضرت علی کے لشکر کی طرف بھیجا.حضرت
علی کی فوج کے آگے آگے
سبائی لوگ تھے.وہ نہیں چاہتے تھے کہ حضرت عائشہ اور حضرت علیؓ کے مابین صلح ہو اس
لئے جب کعب قرآن شریف لے کر آئے اور صلح کے لئے بلایا تو سپاہیوں نے ان کو قتل کر
دیا اور حضرت عائشہ کے ہودہ پر تیر برسانے شروع کر دئے تا مسلمانوں میں لڑائی شروع ہو
جائے اور فتنہ وفساد کی آگ بجھنے نہ پائے.
Page 256
253
مندرجہ بالا حوالہ جات سے ناظرین اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عبداللہ ابن سباء اور اس کے
اتباع کیسی خطرناک قوم تھی اور یہی وہ لوگ تھے جو حضرت علی کو خدا کہتے تھے اور اس کی پارٹی
کے لوگوں کو مدائن کی طرف جلا وطن کر دیا مگر وہ لوگ پھر بھی اپنی شرارت سے باز نہ آئے.اور جن لوگوں
کا ذکر عکرمہ کی روایت میں ہے کہ وہ اسی پارٹی کے آدمی تھے پس اگر
یہ مان بھی لیا جائے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس پارٹی کے بعض افراد کو کسی رنگ میں
قتل کیا تو وہ ان کے ارتداد کی وجہ سے نہ تھا بلکہ اس لئے تھا کہ یہ ایک مفسدوں کی جماعت
تھی جن کو نہ حضرت علیؓ سے محبت تھی نہ اسلام سے بلکہ جو دراصل مسلمانوں کی سماج کے
دشمن تھے اور ان کے عصا کو توڑنا چاہتے تھے.پس ان کی مثال سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اگر کوئی شخص اسلام ترک کر کے ہندو یا
مسیحی ہو جاوے تو اس کو قتل کر دیا جاوے.ابن سباء اور اس کے ساتھیوں کی مثال محض
مرتدین پر ہرگز چسپاں نہیں ہوسکتی ہے
اسی طرح خلفائے راشدین کے عہد میں کوئی بھی ایسی مثال نہیں مل سکے گی جس کی نسبت
قتل مرتد کے حامی یہ ثابت کر سکیں کہ فلاں صورت میں محض ارتداد اور خالص ارتداد کے
لئے کسی مرتد کو محض مذہبی بناء پر قتل کیا.تمام تاریخی مرتدین کی نسبت تاریخ بیان کر رہی ہے
کہ ان سے قتال خالص ارتداد کی وجہ سے نہیں کیا گیا.اور اگر بالفرض کوئی ایسی روایت بھی
ہو جس کے متعلق کوئی تاریخی ثبوت نہ مل سکے تو ایسے شاذ و نادر واقعات کو کثرت کے تابع
کرنا پڑے گا اور یہی نتیجہ نکالنا پڑے گا کہ یہ صورت بھی عام صورت کے مطابق ہے.ہرا یک واقعہ ہمیں پوری تفصیل کے ساتھ نہیں پہنچا مگر ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ زمانہ جنگ و جدال
لے حضرت علی کا ایک اور قول بھی ہمارے دعوی کی تائید کرتا ہے.آپ نے فرمایا تجهزوا لقتال المارقين
المختلین جس کے معنے نہا یہ لا بن اثیر جلد 3 صفحہ 190 میں یہ لکھے ہیں کہ ایسے لوگوں کے قتال کی تیاری کرو
جو احکام دین کی حدود اور اطاعت امام سے نکل گئے ہیں اور جنہوں نے امام کے خلاف بغاوت اور سرکشی کی ہے.نیز دیکھو لسان العرب لفظ غلام.
Page 257
254
اور سیاسی بے چینی کا زمانہ تھا اور جیسا کہ تاریخ ثابت کر رہی ہے کہ اس زمانہ میں ارتداد کے
معنے صرف ارتداد نہ تھے مگر اس زمانہ کے مرتد سب حربی مرتد ہوتے تھے جو اسلام کے
سیاسی دشمن بن جاتے تھے اور اسلام کو ان سے اسی طرح کا خطرہ ہوتا جس طرح دوسرے
دشمنوں سے.اب میں خدا تعالیٰ کے فضل و رحم سے صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کے
عہد کے حالات سے بھی فارغ ہو گیا.اور ناظرین نے دیکھ لیا کہ خلفائے راشدین نے
مرتدین سے اُن کے ارتداد کی وجہ سے قتال نہیں کیا اور نہ کسی مرتد کو محض ارتداد کی وجہ سے
قتل کیا بلکہ اُن کا قتال بغاوت کو روکنے اور فتنہ و فساد کو دُور کرنے اور اسلام اور اہلِ اسلام کی
حفاظت کے لئے تھا.اس حصہ مضمون کو ختم کرنے سے پہلے میں ایک اور روایت پر بھی نظر کرنا ضروری سمجھتا ہوں جو
قتل مرتد کے حامیوں نے اپنے دعوی کے ثبوت میں پیش کی ہے.وہ روایت یہ ہے کہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہما
کو یمن کی طرف بھیجا اور ہر ایک کے لئے الگ الگ علاقہ مقرر فرما دیا.اور اُن کو چلتے وقت
یہ نصیحت فرمائى يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا“ یعنی تم دونوں کا فرض ہے کہ تم
لوگوں کو آسانی دو اور تنگی نہ دو.اور لوگوں کو بشارت دو اور دین کی طرف محبت سے راغب کرو
اور لوگوں کے دل میں دین سے نفرت پیدا نہ کرو.دونوں اپنے اپنے علاقہ میں پھرتے تھے
اور جب اُن میں سے ایک اپنے دورہ میں دوسرے کے قریب جاتا تو اُس سے ملاقات
کرتا.ایک دن جب حضرت معادؓ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے ملنے کے لئے آئے تو وہاں
ایک شخص دیکھا جس کو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے باندھ کر اپنے پاس بٹھایا ہوا تھا.حضرت
معاذ نے دریافت کیا یہ شخص کون ہے.جواب دیا گیا کہ یہودی تھا.پہلے مسلمان ہوا تھا پھر
مرتد ہو گیا.حضرت معادؓ نے فرمایا کہ میں اپنی سواری سے نہیں اتروں گا جب تک تم اس کو قتل
نہ کر دو اور فرمایا کہ یہی خدا تعالیٰ کا اور اس کے رسول کا فیصلہ ہے (قضاء الله ورسوله).
Page 258
255
میں کہتا ہوں کہ یہ اُسی قسم کا قتل ہے جس طرح حضرت
ابوبکر کے عہد میں مرتدین
کو قتل کیا گیا اور اس کے دلائل حسب ذیل ہیں.ا.حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ اس شخص کا قتل کرنا اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہے
اللہ تعالیٰ کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے.اُس میں لکھا ہے کہ کسی شخص کو صرف دو
صورتوں میں قتل کرنا جائز ہے تیسری کوئی صورت نہیں.اوّل قصاص میں.دوم فساد فی
الارض میں.چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:.مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ
النَّاسَ جَمِيعًا (المائدة: 33)
جو کسی شخص کو بغیر اس کے کہ اس نے
قتل کیا ہو یا ملک میں فساد پھیلا یا ہو قتل کر دے تو گویا
اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا.فساد فی الارض کی ایک صورت آیت مذکورہ بالا سے اگلی آیت میں بیان فرمائی گئی
ہے جو یہ ہے:.إِنَّمَا جَزَ وُا الَّذِينَ يُحَارِبُوْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا
أَنْ تُقَتَلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ
أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ (المآئدة: 34)
جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور فساد کی غرض سے ملک میں جنگ
کی آگ بھڑ کانے کے لئے دوڑتے پھرتے ہیں ان کی مناسب سزا یہی ہے کہ ان میں
سے ایک ایک کو قتل کیا جائے یا صلیب پر لٹکا کر مارا جائے یا ان کے ہاتھ اور ان کے
پاؤں مخالفت کی وجہ سے کاٹ دیئے جائیں یا انہیں ملک سے نکال دیا جائے.پس حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کا یہ فرمانا کہ اس شخص کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق
قتل کروایا جاتا ہے ظاہر کرتا ہے کہ اُس کے قتل کی وجہ فساد فی الارض یا محاربہ تھی محض ارتداد
Page 259
256
اُس کی وجہ نہ تھی.کیونکہ میں قرآن شریف کی آیات سے ثابت کر چکا ہوں کہ اسلام میں
محض ارتداد کے لئے کوئی دنیوی سزا مقرر نہیں کی گئی اور کسی کو محض ارتداد کے لئے قتل کرنا
قرآن شریف کی صریح تعلیم کے خلاف ہے.دوم.حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کا یہ فرمانا کہ اس شخص کا قتل کرنا نہ صرف قرآن
شریف بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بھی مطابق ہے اس سے بھی یہی ظاہر ہوتا
ہے کہ اس شخص کو محض ارتداد کے لئے قتل نہیں کیا گیا کیونکہ جیسا میں ثابت کر چکا ہوں اس
امر کے متعلق جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق حسب اصول فقہاء
ومحد ثین کی نظر جاتی ہے تو اُس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ اسی مرتد کے قتل کا حکم ہے جو
محارب ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی اسی کے مطابق تھا کیونکہ آپ نے کبھی
کسی مرتد کو محض ارتداد کے لئے قتل نہیں کروایا بلکہ انہی کو قتل کروایا جو محارب تھے.اور اُن
میں سے بھی بعض کو بعض معزز صحابہ کی سفارش پر معاف فرما دیا جو صریح ثبوت اس امر کا
ہے کہ ارتداد کے لئے قتل شرعی حد نہیں ہے اور نیز ثابت ہے کہ بعض مرتدین کو آپ نے
با وجود قدرت کے قتل نہیں کروایا.پس سنت نبوی سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ محض ارتداد
کے لئے قتل کی سزا شریعت نے مقرر نہیں کی اور یہ کہ جن مرتدین کو قتل کیا گیا اُن کو ارتداد کی
وجہ سے نہیں بلکہ محاربہ کی وجہ سے قتل کیا گیا اور یہی قرآن شریف کی تعلیم ہے.پس حضرت
معاذ کا یہ فرمانا کہ اس شخص کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ کے مطابق قتل کیا جاتا ہے
یہی ظاہر کرتا ہے کہ اس کو حربی ہونے کی وجہ سے قتل کیا گیا.سوم.یمن کے اُس وقت کے حالات بھی اسی امر کی تائید کرتے ہیں کہ اس کو محض
ارتداد کی وجہ سے قتل نہیں کیا گیا کیونکہ ہر ایک تاریخ دان اس امر سے بخوبی واقف ہے کہ جو
ارتداد بقیہ ملک عرب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر واقع ہوا وہ ملک یمن میں
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انہی دنوں میں پیدا ہو گیا تھا جبکہ حضرت معاذ یمن
Page 260
257
میں متعین تھے اور یہ فتنہ اسود عنسی کی وجہ سے ہوا جس کی مختصر کیفیت میں اوپر بیان کر چکا
ہوں.پس یہ سیاسی رنگ کا ارتداد حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے وقت میں ملک یمن میں واقع
ہو چکا تھا اور اسود عنسی کے قتل کے بعد بھی اس کی انگار یاں بالکل نہیں بجھی تھیں کیونکہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساتھ معاوہی آگ پھر شعلہ زن ہوئی.پس یہ ایک ثابت شدہ
امر ہے کہ حضرت معادؓ کی موجودگی میں یمن میں اسی رنگ کا فتنہ نہایت خطرناک طور پر نمودار
ہو گیا تھا.پس ایسے زمانہ میں جبکہ مرتدین یمن میں اسلامی حکومت کے خلاف جنگ کے لئے
کھڑے ہو گئے تھے اگر حضرت معاذ نے ایک مرتد کو قتل کرنے کا حکم دیا تو اس سے اسی نتیجہ کی
تائید ہوتی ہے کہ وہ مرتد حربی تھا.اور ایسے حالات کے ماتحت اس واقعہ سے کوئی شخص قطعی اور
یقینی طور پر یہ نتیجہ نہیں نکال سکتا کہ اسلام میں محض ارتداد کی سزا قتل ہے.چہارم.پھر میں کہتا ہوں کہ اسی راوی کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے بعض ایسے الفاظ
نقل کروائے ہیں جو اس بات کی شہادت دے رہے ہیں کہ حضرت معادؓ اور حضرت ابوموسیٰ
اشعری نے محض ارتداد کی وجہ سے اُس شخص کو قتل نہیں کیا کیونکہ اسی حدیث میں لکھا ہے کہ
رخصت کرتے وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو اصولی رنگ میں یہ نصیحت فرمائی
تھی یسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفّرا، یعنی دین کے معاملہ میں تم لوگوں کو آسانی اور
سہولت دو.اُن پر تنگی نہ ڈالو اور لوگوں کو بشارت اور خوشخبری دو اور ایسا طریق اختیار کرو جس
سے لوگ اسلام کی طرف رغبت کریں اور لوگوں کو اسلام سے متنفر نہ کرو.اس وصیت مقدسہ میں صاف یہ تعلیم دی گئی کہ دین کے معاملہ میں جبر سے کام نہ
لینا.کیونکہ جبر کا استعمال اس وصیت کے بالکل مخالف ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان صحابیوں کو رخصت کرتے وقت فرمائی.اور حامیان قتل مرتد اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ قتل
مرتد ایک جبر کا طریق ہے اس طریق کا استعمال اُس وصیت کے خلاف تھا جو آنحضرت صلی
اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو رخصت کرتے وقت فرمائی اور ہم ایک آن کے لئے بھی یہ
Page 261
258
ماننے کے لئے تیار نہیں کہ ان جلیل القدر صحابیوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کو
پس پشت ڈال دیا.اگر ایک شخص کو اس لئے قتل کیا جائے کہ اس نے اسلام کو کیوں ترک کیا
تو اس سے نہ صرف ایسے شخص کے دل میں نفرت پیدا ہوگی جس نے اسلام کو ترک کیا بلکہ اس
سے دوسرے لوگوں کے دلوں میں بھی نفرت پیدا ہوگی اور کوئی شخص بھی ایسے مذہب کو پسند
نہیں کرے گا جس کے ترک کرنے کی سزا قتل ہو.پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ
وصیت ایک طرف تو اس عقیدہ کی تردید کر رہی ہے کہ اسلام میں محض ارتداد کی سزا قتل ہے
اور اگر اس وصیت کے کچھ معنی ہیں تو پھر اسلام میں ارتداد کی سزا قتل نہیں ہوسکتی.اور دوسری
طرف یہی وصیت یہ بھی ثابت کر رہی ہے کہ وہ صحابی اس وصیت کی موجودگی میں کسی شخص کو
محض ارتداد کی وجہ سے
قتل نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ایسا کرنا اُس وصیت کی صریح خلاف ورزی
ہے.پس اس حدیث میں اس وصیت کا موجود ہونا یہ ثابت کر رہا ہے کہ اُس شخص کو محض
ارتداد کی وجہ سے
قتل نہیں کیا گیا بلکہ اس فتنہ کی وجہ سے قتل کیا گیا جو اس زمانہ میں ملک یمن
میں پیدا ہو گیا تھا.پنجم.اگر مولوی صاحبان کو ان سب باتوں سے انکار ہو اور ان کو اسی بات پر اصرار
ہو کہ اُس شخص کو حضرت معاذ نے محض ارتداد کے لئے قتل کیا تو ایسی صورت میں اُن سے
کہوں گا کہ اچھا میں تسلیم کر لیتا ہوں کہ حضرت معاذ نے ایسا ہی کیا مگر مجھے بتاؤ کہ ایسی
صورت میں تمہارے دواوین حدیث و فقہ کیا فتوی دیتے ہیں.کیا شریعتِ اسلام میں یہ
ایک مسلم اور متفقہ مسئلہ ہے کہ ایک صحابی کا فعل حجت شرعیہ سمجھی جاتی ہے.کیا تم مجھے دکھا
سکتے ہو کہ اہل اسلام میں متفقہ اور متحدہ طور پر یہ امر مسلم ہے کہ ہر ایک صحابی کا ہر ایک فعل ایک
حجت شرعی ہے.کیا آپ لوگوں کو اس بات
کا علم نہیں کہ اہلحدیث کے نزدیک صحابی کا قول و
فعل حجت شرعیہ نہیں.کیا آپ نہیں جانتے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ صحابی کے قول و فعل کو ہر
گز حجت نہیں سمجھتے.کیا آپ کو معلوم نہیں کہ اہل فقہ حنفیہ صرف ایسے امور میں فعل صحابی کی
Page 262
259
پیروی کرتے ہیں جنہیں قیاس کا دخل نہ ہو اور اگر وہ امراجتہاد سے تعلق رکھتا ہے تو پھر صحابی
کی تقلید ضروری نہیں سمجھتے.اور یہ دونوں صحابی وہ ہیں جن کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
رخصت کرتے وقت ہدایت دی تھی کہ اگر کوئی بات تم قرآن وسنت میں نہ پاؤ تو اجتہاد کر
لینا.اس ہدایت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اُنہوں نے اس موقع پر اجتہاد سے کام لیا ہے اور
اجتہادی امور میں مسلمانوں کا کوئی فرقہ بھی کسی صحابی کے قول یا فعل کو حجت نہیں سمجھتا.نیز
یہ بات بھی نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ اور
حضرت ابو موسیٰ اشعری کو یہ نہیں فرمایا کہ جو بات قرآن میں نہ ہو اُس کے متعلق اجتہاد کر
لینا بلکہ فرمایا کہ جو بات تم قرآن میں نہ پاؤلے اُس کے بارے میں تم اجتہاد سے کام لینا یہ
الفاظ بھی پُر حکمت ہیں.ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر ایک بات معاذ اور ابو موسیٰ کو
قرآن شریف میں نہ ملتی تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ اُس کے متعلق قرآن شریف میں
کوئی ہدایت موجود ہی نہ تھی.پس اس صورت میں اگر بالفرض مان بھی لیا جائے کہ
حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے محض ارتداد کی وجہ سے ایک مرتد کو قتل کر دیا تو اُن کے اس
فعل کی وجہ سے آپ کے ہی دواوین فقہ وحدیث ہم کو پابند نہیں کرتے کہ ہم یہ مان لیں
کہ اسلام میں محض ارتداد کی سزا قتل ہے.خصوصاً جب ایسا حکم قرآن شریف کی صریح تعلیم کے خلاف ہے.جو آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے اور نیز اُس وصیت کے خلاف ہے جو آنحضرت
حامیان قتل مرتد نے ایک روایت یہ بھی پیش کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت معاذ کو فرمایا کہ ایک مرتد مرد و عورت
کو قتل کر دینا.اس کے متعلق حاشیہ ھدایہ مولوی محمد سنبلی
جلد 2 صفحہ 353 میں لکھا ہے سندہ لیس بقوى في رجاله کلام یعنی اس روایت کی سند قوی
نہیں اس کے راوی محل اعتراض ہیں علاوہ ازیں یہ حدیث صحیح حدیثوں کے مخالف ہے جن میں عورت کو
قتل کرنے کی صریح مخالفت موجود ہے.اور فقہائے حنفیہ کا عمل بھی اس روایت کے خلاف ہے.
Page 263
260
صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہما کو رخصت کرتے
وقت فرمائی.زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہیں گے کہ انہوں نے اجتہاد سے کام لیا اور اجتہادی
امور میں تمام فرقہائے اسلام کے نزدیک تقلید صحابی واجب نہیں.
Page 264
261
قتل مرتد اور فقہ
قرآن شریف اور حدیث اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت کرنے کے
بعد کہ اسلام میں محض ارتداد کے لئے کوئی سزا مقر نہیں کی گئی ضرورت نہ تھی کہ کتب فقہ کی
طرف رجوع کیا جاوے.لیکن حامیان
قتل مرتد کے اس دعوی کو توڑنے کے لئے کتب فقہ
اُن کے ساتھ ہیں یہ نا مناسب نہ ہوگا کہ کتب فقہ کی طرف بھی توجہ کی جائے تا معلوم ہو سکے
کہ یہ کتابیں اُن کو کہاں تک پناہ دے سکتی ہیں.پس اس غرض سے جب میں کتب فقہ کی
طرف رجوع کرتا ہوں تو مجھے یہ معلوم کر کے نہایت خوشی ہوتی ہے کہ فقہاء میں سے فرقہ
احناف اس اصول میں بالکل ہمارے ساتھ متفق ہے کہ اسلام میں محض ارتداد کی سزا قتل
نہیں ہے.بلکہ مرتد کے قتل کرنے کی اصل وجہ اُس کا حربی ہونا ہے.اس کا ثبوت یہ ہے:.(۱) سب سے پہلے میں فقہ کی مشہور کتاب هـــدایــه کو لیتا ہوں.اُس میں مرتدہ
عورتوں کے متعلق بحث کرتے ہوئے صاحب ہدایہ لکھتا ہے:.ولنا ان النبي عليه السلام نهى عن قتل النساء ولان الاصل تأخير
الأجزية الى دار الآخرة اذ تعجيلها يخل بمعنى الابتلاء وانما عدل
عنه لدفع شر ناجز و هو الحراب ولا يتوجّه ذلك من النساء لعدم
صلاحية البنيه بخلاف الرجال.یعنی مردہ عورت کے نہ قتل کرنے کی دو وجہیں ہیں ایک یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم نے عورتوں
کو قتل کرنے سے منع فرمایا ہے.اور دوسرے یہ کہ سزا دینے سے متعلق اصل یہ ہے کہ اس کو آخرت پر چھوڑ دیا جائے
کیونکہ اس دنیا میں سزا دینا ابتلاء کی حقیقت کو توڑنا ہے اور اگر اس قاعدہ سے عدول کیا جاتا
Page 265
262
ہے تو وہ صرف پیدا ہونے والی شر کو روکنے کی غرض ہوتا ہے اور وہ شر حراب یعنی لڑائی ہے.اور
چونکہ عورتوں میں اپنی پیدائش کی وجہ سے جنگ کی قابلیت نہیں ہوتی.اس لئے اُن
کو قتل نہیں
کیا جاتا.(۲) ھدایہ کے بعد میں فتح القدیر کی شہادت کو پیش کرتا ہوں.دیکھو فتح القدیر کا
مصنف کیسی صفائی سے اس مضمون پر روشنی ڈالتا ہے.وہ لکھتا ہے:.يجب في القتل بالردة ان يكون لدفع شرّ حرابه لا جزاءً على فعل
الكفر لان جزاءه اعظم من ذلك عند الله تعالى فيختص بمن.يتأتى منه الحراب وهو الرجل ولهذا نهى النبي صلى الله عليه
وسلم عن قتل النساء وعلله بانّها لم تكن تقاتل على ماصح من
الحديث فيما تقدّم (فتح القدير جلد 4 صفحه 389)
یعنی مرتد کو قتل کرنے میں یہ واجب ہے کہ وہ اُس کے حراب یعنی جنگ کی شر کوڈ ورکرنے
کے لئے ہو.نہ کہ اُس کو کفر اختیار کرنے کی سزا ہو.کیونکہ کفر کی سزا اللہ تعالیٰ کے
نزدیک اس سے بہت بڑھ کر ہے.پس قتل اسی شخص کے ساتھ خاص ہے جس سے
حراب سرزد ہو اور وہ مرد ہی ہو سکتے ہیں اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ
میں عورتوں
کو قتل کرنے سے منع فرمایا ہے اور اس کو بُرا قرار دیا ہے کیونکہ عورتیں جنگ
نہیں کیا کرتی تھیں.(۳) پھر چلسی میں لکھا ہے :.قال ابن الهمام لا جزاء على فعل الكفر فان جزاءه اعظم عند ال
من ذلك.(چلپی برحاشیہ فتح القدیر صفحہ 388)
یعنی کفر اختیار کرنے کی وجہ سے کسی کو سزا نہیں دی جاتی ہے.کیونکہ کفر کی سزا قتل سے
بڑھ کر ہے اور وہ خدا تعالیٰ خود ہی دے سکتا ہے.
Page 266
263
(۴) پھر عنائیہ میں صفحہ 390 پر لکھا ہے:.لاقتل الا باحراب فكان القتل مستلزم للحراب لان نفس الكفر
ليس يهيج له ولهذا لا يقتل الأعمى والمعقد والشّيخ الفاني.یعنی حراب کے بغیر کوئی قتل نہیں.پس قتل حراب کے لئے مستلزم ہے کیونکہ تنہا کفر کی وجہ
سے کسی کو قتل کرنا جائز نہیں اور یہی وجہ ہے کہ نابینا اور شیخ فانی اور معذور کو قتل نہیں کیا
جاتا.(۵) اب دیکھئے کہ اُس حدیث کے اہل فقہ حنفیہ نے کیا معنی کئے ہیں جس کو آج
قتل مرتد کے دعویدار بڑے زور شور سے پیش کر رہے ہیں.یعنی یہ حدیث من بدل دينه
فاقتلوه فتح القدیر جلد 2 صفحہ 580 میں لکھا ہے: "كذا قوله الله من بدل دينه
فاقتلوه لانه كافر حربى بلغته الدعوة فيقتل للحال من غيرا لتمهال، يعنى
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے جو شخص اپنے دین کو بدل دے اُس کو قتل کر دو.اس کی یہی وجہ ہے کہ وہ حربی کافر ہے اور اُس پر اتمام حجت ہو چکا ہے پس ایسے شخص کو فوراً
قتل کر دینا چاہئے.اور مہلت نہیں دینی چاہیئے.دیکھو اس حدیث میں بھی فقہاء حنیفہ کے
نزدیک ایسا ہی مرتد مراد ہے جو حربی ہو اور اُس کے قتل کی وجہ اُس کا ارتداد نہیں بلکہ اُس کا
حربی ہونا ہے.میرے خیال میں مندرجہ بالا حوالجات سے صاف ظاہر ہے کہ فقہ حنفیہ کے ائمہ اس
اصول میں کلیۂ ہمارے ساتھ متفق ہیں کہ محض ارتداد کی سزا قتل نہیں اور کسی مرتد کو اس لئے
قتل کرنا جائز نہیں کہ اُس نے ارتداد اختیار کیا ہے بلکہ قتل کی وجہ اُس کا محارب ہونا ہے.اور یہی ہمارا اصول ہے جس کو میں نے اس مضمون میں بفضلہ قرآن شریف اور سنت رسول
اور سُنت خلفاء راشدین کے ذریعہ ثابت کیا ہے.اس جگہ قتل مرتد کے دعویدار یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اصول صرف حنفیوں کے نزدیک
Page 267
264
مسلم ہے.دوسرے فرقوں کے فقہاء اس کو تسلیم نہیں کرتے بلکہ اُن کے نزدیک محض ارتداد
ہی موجب قتل ہے.اسی لئے اُن
کا یہ فتوی ہے کہ اگر مرتد پیر فرتوت ہو جس میں قتال تو کجا
چلنے پھرنے کی بھی طاقت نہ ہو اُس کو بھی قتل کر دو.اسی طرح اگر کوئی بڑھیا عورت ہے جو
کسی متنفس کو گزند نہیں پہنچاتی اور بدقسمتی سے ارتداد اختیار کرتی ہے تو اُس بڑھیا کو بھی قتل
کر دو.اگر کوئی نابینا یا لنگڑا لو لا ہے یا بیمار اور ضعیف ہے مثلاً سل کی مرض میں مبتلا ہے اور
چند دن کا مہمان ہے اور شیطانی اغواء سے اسلام سے مرتد ہو کر کوئی اور دین اختیار کرتا ہے
تو ایسے شخص کی گردن پر بھی تلوار چلا دو.غرض اُن کے نزدیک محارب ہونا کوئی شرط نہیں صرف ارتداد ہی ایسا جرم ہے
جس کے لئے قتل کی حد شرعی مقرر ہے عورت ہو ، مرد ہو، بوڑھا ہو ، جوان ہو، بیمار ہو،
تندرست ہو اگر ارتداد اختیار کرے گا تو اس کو فی الفور قتل کر دینا چاہئیے.میں تسلیم کرتا
ہوں کہ یہ عقیدہ بے شک اُس اصول کے خلاف ہے جو ائمہ احناف نے بیان کیا ہے
اور دونوں عقیدوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے.ایک گروہ محض ارتداد ہی کو موجب
قتل ٹھہراتا ہے.دوسرا گروہ محض ارتداد کوقتل کا موجب نہیں ٹھہرا تا بلکہ حراب کو اصل
موجب قتل قرار دیتا ہے.اب ظاہر ہے کہ یہ دونوں عقیدے درست نہیں ہو سکتے.ان
دونوں گروہوں میں سے صرف ایک ہی گروہ حق پر ہوسکتا ہے اور ہمارے نزدیک فرقہ
حنفیہ اپنے اس اصول میں جس کو میں اوپر کتب فقہ کے الفاظ میں نقل کر چکا ہوں حق پر
ہے.کیونکہ ان کا یہ اصول قرآن شریف کی تعلیم کے عین مطابق ہے اور آنحضرت صلی
اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے بالکل موافق ہے.یہ ناممکن ہے کہ ہم دونوں فریق کو
حق پر خیال کریں آخر ایک کو ہی حق پر خیال کیا جائے گا.پس ہمارے نزدیک وہی
اصل درست اور صحیح ہے جو ائمہ فقہ حنفیہ نے بیان کیا ہے اور جس کو میں انہی کے الفاظ
میں اوپر بیان کر چکا ہوں.
Page 268
265
دوسرے گروہ کا اصول کہ محض ارتداد ہی اصل موجب قتل ہے نہایت ہی غلط اصول
ہے جس کی نہ قرآن شریف تائید کرتا ہے اور نہ سنت رسول ﷺ.پس ہم ایسے اصول کو جو
اسلام کے روشن نام پر ایک دھبہ ہے کسی صورت میں قبول نہیں کر سکتے.جب قرآن شریف
کی صریح تعلیم ایسے اصول کے خلاف ہے تو ہم قرآن شریف کی تعلیم کو کس طرح ترک
کر سکتے ہیں.میں کہتا ہوں کہ اگر فقہ حنفیہ کے ائمہ بھی اس کے خلاف کوئی اصول قائم کرتے
یا اگر حنفیوں کا طرز عمل ان کے بیان کردہ اصول کے خلاف ہو تو ہم حق کے کھل جانے پر
حنفیوں کو بھی چھوڑ سکتے ہیں کیونکہ ہمارا ایمان تو خدا اور اس کے رسول پر ہے نہ کسی اور پر.پھر حامیان
قتل مرتد فرماتے ہیں کہ قتل مرتد پر تمام امت کا اتفاق ہے امت کا
اجماع ہو چکا ہے کسی ایک شخص نے بھی اس کے خلاف نہیں کہا.میں کہتا ہوں کہ ان کا یہ
دعوی سرا سر غلط ہے کیونکہ اس اصول میں کہ اسلام میں محض ارتداد کے لئے کوئی دنیوی سزا
مقرر نہیں کی گئی.ائمہ فقہ حنفیہ کا ہمارے ساتھ اتفاق ہے اور انہوں نے اس اصل کو تسلیم کیا
ہے کہ ارتداد کی سزا قتل نہیں بلکہ قتل کی سزا محارب ہونے کی وجہ سے دی جاتی ہے.پھر میں
کہتا ہوں کہ ان کا یہ کہنا بھی غلط ہے کہ ایک شخص واحد نے بھی قتل مرتد سے اختلاف نہیں
کیا.کیونکہ مسلمانوں میں بعض ایسے محقق گزرے ہیں جنہوں نے اس عقیدہ سے کھلے طور
پر اختلاف کیا ہے اور ان کی رائے ہے کہ مرتد کو قتل نہ کیا جائے بلکہ ان کوتو بیہ کی مہلت دی
جائے یہانتک کہ وہ اس دنیا سے اپنی طبعی موت سے گزرجائیں.حافظ ابن قیم کا قول خود
مولوی شبیر احمد صاحب نے پیش کیا ہے اور وہ اس بات کے قائل نہیں کہ اسلام میں محض
ارتداد کی سزا قتل ہے.اسی طرح میں تفاسیر کے حوالجات سے اوپر ثابت کر آیا ہوں کہ بعض ایسے علماء
گزرے ہیں جو قتل مرتد کے قائل نہ تھے.اسی طرح ابراہیم نخعی اور سفیان ثوری کا یہی
مذہب ہے اور یہ لوگ کوئی چھوٹے پایہ کے انسان نہیں چنانچہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ
Page 269
266
کے متعلق کہا گیا ہے کہ وہ حدیث میں امیر المومنین ہیں دیکھو صاحب تهذیب التهذیب
ان کی نسبت کیا لکھتے ہیں :.قال شعبة وابن عتبة و ابو عاصم بن معین و غیر واحد من العلماء سفيان امير
الـمـؤمـنـيـن فـي الـحـديـث و قال ابن المبارك كتبت عن الف و مأة شيخ
ماكتبت عن افضل من سفيان و قال وكيع عن سعيد سفيان أحفظ منى.وقال
ابن مهدى كان وهب يقدم سفيان فى الحفظ على مالك و قال يحيى
القطان ليس احد احب الى من شعبة ولا يعدله احد عندی و اذا خالفه سفیان
اخذت بقول سفيان و قال ابوداؤد بلغني عن ابن معين قال ماخالف احد
سفيان فى شئ الا كان القول قول سفيان قال النسائى هو اجل من ان يقال فيه
ثقة و هو احد الائمة الذين ارجوا ان يكون الله ممن جعله للمتقين اماما.قال
ابن حبان كان من سادات الناس فقها و ورعا و اتقانا
(تهذيب التهذيب جلد 4 صفحہ 114)
یعنی شعبہ اور ابن عتبہ اور ابو عاصم بن معین اور ان کے سوا اور کئی علماء نے کہا ہے کہ
سفیان حدیث میں امیر المومنین ہے اور ابن مالک نے کہا کہ میں نے ایک ہزار ایک سوشیخ
سے احادیث سن کر لکھی ہیں اور ان میں ایک بھی سفیان سے بہتر نہ تھا اور وکیع روایت
کرتے ہیں کہ سعید نے کہا کہ سفیان میری نسبت احادیث کو زیادہ یا در رکھنے والا ہے اور ابن
مہدی نے کہا کہ وہب احادیث کے یاد رکھنے میں سفیان کو مالک پر مقدم کیا کرتا تھا اور
یحی القطان کہتا ہے کہ کوئی شخص مجھے شعبہ سے زیادہ پیارا نہیں اور میرے نزدیک کوئی بھی
اس کے برابر نہیں لیکن اگر سفیان کا قول شعبہ کے خلاف ہو تو میں شعبہ کے مقابل میں
سفیان کے قول کو اختیار کرونگا.اور ابو داؤد کہتا ہے کہ مجھے ابن معین سے یہ روایت پہنچی ہے
کہ اس نے کہا کہ جب بھی کسی کا قول سفیان کے قول کے خلاف ہو تو اصل قول وہی ہوتا
Page 270
267
ہے جو سفیان کا قول ہوتا ہے.نسائی کہتے ہیں کہ سفیان اس تعریف سے بھی بالا تر ہے کہ ان
کی نسبت کہا جائے کہ اس میں نقاہت اور پختگی پائی جاتی ہے اور وہ ان اماموں میں سے
ایک امام ہے جن کی نسبت میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو متقیوں کا سردار بنایا
ہے اور ابن حبان کہتے ہیں کہ وہ تفقہ اور پر ہیز گاری اور رائے کی مضبوطی میں سادات
الناس میں سے ہے.یہ شان ہے اس شخص کی جس نے بعض دوسرے ائمہ کے
علاوہ قتل مرتد کے مسئلہ کا
انکار کیا ہے مگر مولوی صاحب فرماتے ہیں کہ قتل مرتد کے فتویٰ میں کبھی کسی فرد واحد نے بھی
اختلاف نہیں کیا.اور ایسے حدیث کے امام کا قطعی انکار ظاہر کرتا ہے کہ حدیث میں کوئی نص
قطعی قتل مرتد کے لیے موجود نہیں.اگر کوئی نص موجود ہوتی تو حدیث کا ایسا جلیل القدر عالم
قتل مرتد کے مسئلہ کا کبھی صاف انکار نہ کرتا.اسی طرح ابراہیم بھی بھی ایک بڑے پائیڈ کے
فقیہ ہیں اور اپنے وقت کے سب سے بڑے عالم مانے گئے ہیں.اب میں اس سوال کا جواب دے کر کہ زمانہ سلف کے بعض علماء کو قتل مرتد کے متعلق
کیوں ایسی غلطی لگی کہ انہوں نے بلا کسی شرط کے مرتد کے قتل کا فتویٰ دیا ؟ اس مضمون کو ختم کرتا
ہوں.اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ غلط خیال اسی طرح پیدا ہوا جس طرح یہ خیال پیدا ہوا
کہ اسلام ہر ایک مشرک اور بُت پرست کو قتل کرنے کا حکم دیتا ہے.جس طرح بعض
لوگوں نے قرآن شریف کی ایک آدھ آیت سے غلطی سے یہ نتیجہ نکالا کہ ہر ایک مشرک اور
بت پرست کو قتل کرنے کا حکم ہے اور اس کے سیاق وسباق کو نظر انداز کر کے اس کو سب
مشرکوں پر حاوی سمجھ لیا گیا اور قرآن شریف کی قریباً چار صد آیات کو منسوخ قرار دیا.اسی
طرح بعض علماء نے ایسی روایات سے دھو کہ کھایا جن میں مرتدین کے قتل کا ذکر تھا اور ان
روایات کو ہر ایک مرتد پر حاوی سمجھ لیا اور اس امر کی طرف توجہ نہ کی کہ ان روایات میں ایسے
Page 271
268
مرتدین کا ذکر ہے جو محارب ہوں اور یہ نہ دیکھا کہ بعض روایات میں محارب کی شرط موجود
ہے.اس شرط کو نظر انداز کر دیا اور ایسا ہی زمانہ کے حالات کو بھی نظر انداز کیا کہ کن حالات
میں یہ حکم دیا.اس بات کی طرف نہ دیکھا کہ اس زمانہ میں ایک شخص کا ارتداد محض ارتداد تک
ہی محدود نہ رہتا تھا بلکہ مرتد ہوتے ہی وہ دشمنوں سے مل کر مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرتا اور
ایسا شخص دوسرے دشمنوں سے زیادہ خطرناک ہوتا تھا کیونکہ یہ مسلمانوں کے حالات سے
واقف ہوتا..اسی طرح انہوں نے پڑھا کہ فلاں مرتد کو قتل کیا گیا مگر اس پر غور نہ کیا کہ کیوں قتل کیا
گیا.اس کے بعد انہوں نے حضرت ابوبکر اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کے عہد میں مرتدین کی
گردنوں پر تلوار چلتی دیکھی مگر یہ نہ دیکھا کہ یہ تلوار کیوں چلائی گئی.غرض صرف حکم دیکھ لیا اور
تمام دوسرے حالات کو نظر انداز کر دیا.نہ ان جرموں کو دیکھا جو ان مرتدین سے سرزد ہوئے
نہ ان ملکی ضرورتوں اور سیاسی مجبوریوں پر غور کیا جن کی وجہ سے خلفاء راشدین ارتداد کرنے
والوں کے خلاف تلوار کھینچنے پر مجبور ہوئے اور ان تمام واقعات سے غلطی سے یہ نتیجہ نکال لیا
کہ ہر ایک مرتد کی سزا قتل ہے.مگر یہ خوشی کا مقام ہے کہ اگر بعض علماء نے قتل کوارتداد کی سزا
قرار دیا تو بعض علماء نے اس بات کے قبول کرنے سے انکار کیا کہ ارتداد کی سزا قتل ہے اور
صاف الفاظ میں لکھ دیا کہ ارتداد اور کفر کے لئے شریعت اسلام نے کوئی سزا مقرر نہیں کی بلکہ
اس کو عالم آخرت کے لئے چھوڑ دیا ہے.اس عالم میں مرتد کو صرف حراب اور فساد فی الارض
کی وجہ سے قتل کیا جاتا ہے نہ ارتداد کی وجہ سے.اب میں ناظرین کے انصاف پر فیصلہ چھوڑتا ہوں کہ وہ ایک طرف تمام قرآن شریف
کی تعلیم اور اسلامی تعلیم کی روح اور آنحضرت ﷺ کے اعلیٰ اخلاق اور آپ کی تعلیم کو رکھیں.نیز اسلامی تاریخ کے واقعات پر نظر کریں اور دوسری طرف ان علماء کے فتووں کو دیکھیں جو یہ
کہتے ہیں کہ اسلام میں محض ارتداد کی سزا قتل ہے خواہ شیخ فانی ہو جو چلنے پھرنے کی بھی طاقت
Page 272
269
نہ رکھتا ہو یا لنگڑا اور اپانچ ہو یا بیمار ہو جو بوجہ بیماری اپنی چار پائی سے اٹھنے کی بھی طاقت نہ
رکھتا ہو یا ایک بے ضرر بڑھیا عورت ہو ان سب کو بے دریغ قتل کرو.اب آپ ہی فیصلہ
فرما دیں کہ آیا یہ فتویٰ اسلام کے نام کو روشن کرنے والا ہے یا اس کو بدنام کرنے والا ہے.دو
را ئیں ہمارے سامنے ہیں ایک یہ کہ اسلام میں محض ارتداد کی سزا قتل ہے ارتداد کر نے والا
کوئی ہو اس کو قتل کیا جائے.حراب کی کوئی شرط نہیں اور مرتد کو مجبور کرنا چاہیئے کہ وہ دوبارہ
اسلام کو قبول کرے ورنہ اس
کو قتل کر دینا چاہیئے.دوسری رائے یہ ہے کہ ارتداد کی سزا قتل نہیں
ہے بلکہ قتل کیلئے حراب اور فساد فی الارض کی شرط ہے.ارتداد یا کفر کی سزا دینا کسی حکومت کا
کام نہیں یہ خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اس لئے اس کو آخرت پر چھوڑنا چاہیئے اور دین میں
جبر جائز نہیں.اب میں اس امر کا فیصلہ کہ ان دو راؤں میں سے کون سی رائے اسلام کی تعلیم
کے موافق ہے اور کون سی مخالف ناظرین پر چھوڑتا ہوں وہ فیصلہ کر لیں کہ ان دونوں راؤں
میں سے کونسی وہ رائے جو اسلام کی تعلیم اور اس کی روح کے مطابق ہے اور کونسی وہ رائے ہے
جو نہ صرف اسلام کی تعلیم کے خلاف ہے بلکہ اسلام کو بدنام کرنے والی اور اس کے روشن چہرہ
پر ایک بدنما داغ ہے.میں یقین کرتا ہوں کہ ہر ایک شخص جو انصاف کے ساتھ بغیر کسی
تعصب کے اپنی رائے کا اظہار کرے گا وہ یقیناً یہی فیصلہ کرے گا کہ وہی رائے اسلامی تعلیم
کے مطابق اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے موافق ہے جس کی رو سے یہ قرار
دیا گیا ہے کہ ارتداد اور کفر کی سزا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور وہ لوگ غلطی پر ہیں جو محض
ارتداد کو قتل کا موجب قرار دیتے ہیں اور جن کی یہ رائے ہے کہ ہر ایک مرتد کو قتل کر دینا چاہیئے
خواہ وہ بُڑھیا عورت ہو یا لنگڑا اور اپانچ ہو یا بیمار ہو کیونکہ یہ تعلیم اسلام کی تعلیم اور
آنحضرت ﷺ کے اسوہ مبارکہ کے بالکل مخالف ہے.آخر میں میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ہمارے سینوں کو اسلام کی تعلیم کے
سمجھنے کے لئے کھول دے اور ہمیں حقیقی اور سچے اسلام کی اتباع اور تبلیغ کی توفیق بخشے اور
Page 273
270
ہمارے بھولے ہوئے بھائیوں کی آنکھوں کو کھولے تا وہ دیکھیں کہ وہ کیا ہی غلط راستہ ہے
جس کو انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے.ان کو توفیق بخشے کہ وہ اسلام کو بدنام کرنے والے
خیالات اور اعمال سے تائب ہو کر حق کو قبول کریں.واخر دعوانا ان الحمد لله ربّ العالمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.خاکسار شیر علی عفی عنہ
از قادیان
9 جمادی الاولی 1344 هجری مطابق 26 نومبر 1925ء
على صاحبه التحيّة والسّلام