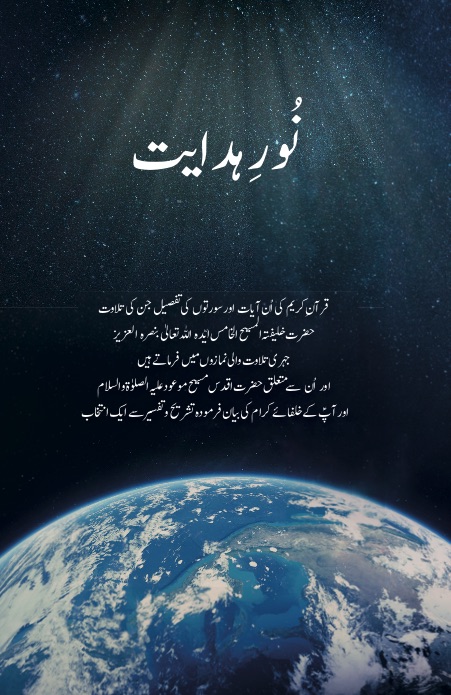Complete Text of Noor-eHidayat
Content sourced fromAlislam.org
Page 1
نُورِ ہدایت
قرآن کریم کی ان آیات اور سورتوں کی تفصیل جن کی تلاوت
حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز
جہری تلاوت والی نمازوں میں فرماتے ہیں
اور اُن سے متعلق حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام
اور آپ کے خلفائے کرام کی بیان فرمودہ تشریح و تفسیر سے ایک انتخاب
مرتبه
نصیر احمد قمر
Page 2
نُورِ ہدایت
Noor-e-Hidaayat
(The Guiding Light-Urdu)
A collection of verses and chapters of the Holy Quran
recited aloud in the various congregational prayers by
Hazrat Khalifatul-Masih V (may Allah be his Helper),
along with their commentary as expounded by the
Promised Messiah (peace be upon him) and his
successors.Compiled by Naseer Ahmad Qamar
First Published in UK in 2018
OIslam International Publication Limited.Published by:
Islam International Publication Ltd.Unit 3, Bourn Mill Business Park
Guildford Road
Farnham, Surrey, GU9 9PS
United Kingdom
No part of this publication may be reproduced or
transmitted in any form or by any means, electronic or
mechanical, including photocopy, recording or any
information storage and retrieval system, without prior
written permission from the Publisher.For further information you may visit
www.alislam.org
ISBN: 978-1-84880-138-7
Page 3
فهرست عناوین
عنوان
صفحہ نمبر
V
1
7
15
16
19
23
25
27
157
303
399
465
473
491
507
نمبر شمار
پیش لفظ
نمازوں میں آنحضرت مالی اسکیم کی تلاوت فرمودہ آیات اور سورتیں
نمازوں میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تلاوت فرمودہ آیات اور سورتیں
نمازوں میں حضرت خلیفتہ امسیح الاول کی تلاوت فرمودہ آیات اور سورتیں
نمازوں میں حضرت خلیفہ المسیح الثانی کی تلاوت فرمودہ آیات اور سورتیں
نمازوں میں حضرت خلیفتہ المسیح الثالث کی تلاوت فرمودہ آیات اور سورتیں
نمازوں میں حضرت خلیفہ المسیح الرابع کی تلاوت فرمودہ آیات اور سورتیں
نمازوں میں حضرت خلیفہ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کی تلاوت
فرمودہ آیات اور سورتیں
سورة الفاتحه
سورة البقرة - آيات 1 تا 17
سورة البقرة آيات 255 258
سورة البقرة آيات 287285
سورة آل عمران آیات 26 تا 31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
سورة آل عمران - آیات 191 تا 195
15 سورة بنی اسرائیل.آیات 79 تا 85
16
ـورة الكهف آیات 01 تا 11
Page 4
نمبر شمار
17
18
19
20
عنوان
سورة الكهف آيات 103 تا 111
سورة حم السجدة آيات 31 37
سورة الحشر - آيات 19 تا 25
سورة الاعلى
21 سورة الغاشيه
22 سورة الشمس
23 سورة الضحى
24
25
سورة الم نشرح
سورة التين
26 سورة الزلزال
27 سورة التكاثر
28
سورة الفيل
29 سورة القريش
30
31
32
33
34
سورة الكافرون
سورة النصر
سورة اللهب
سورة الاخلاص
سورة الفلق
35 سورة الناس
IV
519
547
603
649
695
743
775
793
819
835
863
889
931
989
1011
1051
1067
1091
1153
Page 5
بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلى على رسوله الكريم وعلى عبدة المسيح الموعود
پیش لفظ
18 مئی 1996ء کو ہیمبرگ ( جرمنی ) میں واقفین کو بچوں اور بچیوں کی ایک کلاس حضرت خلیفہ المسیح
الرابع رحمہ اللہ کے ساتھ منعقد ہوئی.اس کلاس کے دوران حضور رحمہ اللہ نے ان سے پوچھا کہ اذان کے
بعد کی دعا کس کو آتی ہے تو سوائے ایک آدھ کے کسی کو بھی یہ دعا یاد نہیں تھی اور اس کا ترجمہ بھی کسی کو
نہیں آتا تھا.حضور رحمہ اللہ نے اچھی طرح سمجھا کر اذان کے بعد کی دعا اور اس کا ترجمہ سکھایا اور تاکید
فرمائی کہ آپ نظمیں یا دعا ئیں جو کچھ بھی یاد کریں اس کے ترجمہ و مفہوم کو بھی اچھی طرح یاد کریں.اسی
تسلسل میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ :
بچوں کو خصوصیت سے اور بڑوں کو بھی وہ آیتیں یاد کرنی چاہئیں جن کی نمازوں میں تلاوت کرتا
ہوں اور اکثر میں فجر ، مغرب اور عشاء کی نمازوں میں بدل بدل کر تلاوت کرتا ہوں.“
حضور رحمہ اللہ نے فرمایا کہ :
یہ آمیتیں جو میں نے پچنی ہیں کسی مقصد کے لئے پچھنی ہیں.اگر ان
کا ترجمہ آتا ہو تو اس کا دل پر
اثر پڑے گا.اگر مطلب نہ آتا ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں.“
اسی طرح حضور رحمہ اللہ نے تاکیدی ہدایت فرمائی کہ:
جوسورت تلاوت کریں اس کا ترجمہ ضرور آنا چاہئے.ترجمہ کو غور سے پڑھیں اور یاد کریں اور اتنا
یاد کریں کہ ادھر تلاوت ہو رہی ہو اور اُدھر آپ کے دل میں اس کا مضمون اتر رہا ہو حتی کہ آپ کا دل
قرآن کی عظمت سے بھر جائے.“
الفضل انٹرنیشنل 7 تا 13 جون 1996 صفحہ 9)
نے حضور رحمہ اللہ کی نمازوں میں تلاوت فرمودہ
اپریل 1997ء میں
آیات کو یکجا کر کے مع ترجمہ شائع کیا.کے آخر پر انہوں نے اس کا دوسرا ایڈیشن تیار کیا
جس کے آغاز میں ایک تحقیقی اور معلوماتی نوٹ بھی شامل کیا گیا جس میں ان آیات و سور قرآنی کی
Page 6
تفصیل درج کی گئی جو آنحضرت صلی اللہ علیہ سلم اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوة والسلام اور
حضرت خلیفہ المسیح الاول رضی اللہ عنہ، حضرت خلیفہ المسح الثانی رضی اللہ عنہ، حضرت خلیفۃ المسیح الثالث
حم الله اورضرت خلیفہ مسیح اربع حجم ال جی تلاوت والی نمازوں میں تلاوت فرماتے تھے.اسی طرح جو آیات و سور حضرت خلیفہ اسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نمازوں میں تلاوت
فرماتے ہیں ان کی تفصیل بھی درج کی گئی.حضور انور ایدہ اللہ تعلی بنصرہ العزیز کیاجازت سے تحقیقی نوٹ اس کتاب میں بھی شامل ہے.اس کے علاوہ امیر المومنین حضرت خلیفتہ امسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کی ہدایت پر وہ تمام
آیات و سور قرآنی جن کی حضور انور ایدہ اللہ جہری تلاوت والی نمازوں ( یعنی فجر ، مغرب، عشاء اور
جمعہ ) میں تلاوت فرماتے ہیں ان کا عربی متن مع ترجمہ اور اسی طرح ان کی مختصر تشریح و تفسیر کو شامل
کیا گیا ہے تا کہ افراد جماعت جب ان آیات و سور کی تلاوت کریں یا سنیں تو ان کے مضامین بھی ان
کے پیش نظر ر ہیں اور ان کے دل قرآن کی عظمت سے بھر جائیں.اس زمانہ میں اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظل کامل اور آپ کے عظیم روحانی فرزند
حضرت اقدس مسیح موعود و مہدی معہود علیہ الصلوۃ والسلام کو اس لئے مبعوث فرمایا کہ تا تعلیمات حقہ
قرآنی کو ہر قوم اور ہر ملک میں شائع اور رائج فرماوے.حضور فرماتے ہیں:
خداوند تعالیٰ نے اس احقر العباد کو اس زمانہ میں پیدا کر کے اور صد با نشان آسمانی اور خوارق
غیبی اور معارف و حقائق مرحمت فرما کر اور صد با دلائل عقلیہ قطعیہ پر علم بخش کر یہ ارادہ فرمایا ہے
که تا تعلیمات حقہ قرآنی کو ہر قوم اور ہر ملک میں شائع اور رائج فرماوے اور اپنی حجت ان پر
پوری کرے.“
اسی طرح آپ نے فرمایا:
( براہین احمدیہ.روحانی خزائن جلد اوّل صفحہ 596 حاشیہ در حاشیہ نمبر 3)
جاننا چاہئے کہ کھلا کھلا اعجاز قرآن شریف کا جوہر ایک قوم اور ہر ایک اہلِ زبان پر روشن ہو
سکتا ہے جس کو پیش کر کے ہم ہر ایک ملک کے آدمی کو خواہ ہندی ہو یا پارسی یا یوروپین یا امریکن
یا کسی اور ملک کا ہوملزم و ساکت ولا جواب کر سکتے ہیں ، وہ غیر محدود معارف و حقائق وعلوم حکمیہ
VI
Page 7
قرآنیہ ہیں جو ہر زمانہ میں اُس زمانہ کی حاجت کے موافق کھلتے جاتے ہیں اور ہر ایک زمانہ کے
خیالات کا مقابلہ کرنے کے لئے مسلح سپاہیوں کی طرح کھڑے ہیں..کھل کھلا اعجا ز اس کا تو یہی
ہے کہ وہ غیر محدود معارف و دقائق اپنے اندر رکھتا ہے.جو شخص قرآن شریف کے اس اعجاز کو
نہیں مانتا وہ علم قرآن سے سخت بے نصیب ہے....قرآن شریف کے عجائبات کبھی ختم
نہیں ہو سکتے اور جس طرح صحیفہ فطرت کے عجائب و غرائب خواص کسی پہلے زمانہ تک ختم
نہیں ہو چکے بلکہ جدید در جدید پیدا ہوتے جاتے ہیں یہی حال ان صُحف مطہرہ کا ہے تا خدائے
تعالیٰ کے قول اور فعل میں مطابقت ثابت ہو.“
اسی طرح فرمایا:
قرآن شریف کے عجائبات اکثر بذریعہ الہام میرے پر کھلتے رہتے ہیں.اور اکثر ایسے ہوتے
ہیں کہ تفسیروں میں ان کا نام و نشان نہیں پایا جاتا.یہ بھی یا درکھیں کہ قرآن شریف کے ایک معنے
کے ساتھ اگر دوسرے معنے بھی ہوں تو ان دونوں معنوں میں کوئی تناقض پیدا نہیں ہوتا اور نہ ہدایت
قرآنی میں کوئی نقص عائد حال ہوتا ہے.بلکہ ایک نور کے ساتھ دوسرا نور مل کر عظمت فرقانی کی روشنی
نمایاں طور پر دکھائی دیتی ہے.اور چونکہ زمانہ غیر محدود انقلابات کی وجہ سے غیر محدود خیالات کا بالطبع
محرک ہے لہذا اس کانٹے پیرا یہ میں ہو کر جلوہ گر ہونا یا نئے نئے علوم کو بمنصہ ظہور لانا، نئے نئے
بدعات اور محدثات کو دکھلانا ایک ضروری امر اس کے لئے پڑا ہوا ہے....قرآن ہلا کریب غیر محدود
معارف پر مشتمل ہے اور ہر یک زمانہ کی ضرورات لاحقہ کا کامل طور پر متکفل ہے.66
(ازالہ اوہام.روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 255 تا264)
الغرض قرآن مجید اور احادیث نبویہ کی پیشگوئیوں کے مطابق ممکنتِ دین اسلام اور تعلیمات حقہ
قرآنی کی اشاعت و ترویج کے لئے اس زمانہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت اقدس مسیح موعود
علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا.چنانچہ آپ اور آپ کے بعد آپ کے خلفائے کرام ہی وہ مقدس
اور مبارک وجود ہیں جن کے ذریعہ سے تعلیم کتاب و حکمت اور اشاعت نور ہدایت قرآنی کا کام
ساری دنیا میں جاری ہے.اس لئے ان آیات و سور قرآنی کی تشریح و تفسیر کے لئے انہیں مطہر و
مقدس وجودوں کی بیان فرمودہ تفاسیر سے استفادہ کیا گیا ہے.حقائق و معارف قرآنی پر مشتمل
VII
Page 8
جواہرات کے یہ خزانے اپنے حسن و رعنائی اور چمک دمک میں بے نظیر اور اپنی وسعت و گہرائی
میں بیکراں اور لازوال اور لامتناہی ہیں.اور ضرورتِ زمانہ اور اقتضائے حال کے مطابق ان کا ظہور
ہوتا چلا جاتا ہے.ان پاک وجودوں کی بیان فرمودہ آسمانی اور نورانی تفسیر القرآن کے ہزار ہا صفحات
پر مشتمل مواد میں سے یہ انتخاب محض بطور نمونہ کے ہے.امید ہے کہ اس کا مطالعہ افراد جماعت کے دلوں میں نہ صرف قرآن کریم کی محبت اور اس کے
عرفان میں اضافہ کا موجب ہو گا بلکہ ان کے اندر حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے
خلفائے کرام کے فرمودات اور تحریرات کے بالاستیعاب مطالعہ اور تدبر قرآن اور فہم و تعلیم قرآن
کے لئے ایک ذوق اور شوق پیدا ہوگا اور وہ انوار قرآنی سے اپنے قلوب و اذہان اور اپنے وجودوں کو
منور کر کے اس نورِ ہدایت کو آگے پھیلاتے ہوئے خیر الرسل ، خاتم الانبیاء حضرت اقدس
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نہایت ہی مبشر و مبارک نوید کا مصداق بنے کی ہر ممکن سعی کریں گے
جس میں آپ نے اپنی امت سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا تھا کہ خَيْرُكُمْ مَّنْ تَعَلَّمَ
الْقُرْآنَ وَعَلَّمہ یعنی تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو پہلے خود قرآن سیکھے اور پھر دوسروں کو بھی
سکھائے.اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو.خاکسار
نصیر احمد قمر
( ایڈیشنل وکیل الاشاعت.لندن )
نومبر 2017ء
VIII
Page 9
نمازوں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
تلاوت فرمودہ آیات اور سورتیں
نماز
نام سورة
سورة ق
روایت
روایت
حوالہ
مسلم کتاب الصلوة
رض
سورة المومنون
حضرت جابر بن سمرة باب القراءة في الصبح
روایت
مسلم كتاب الصلوة
کا ابتدائی حصہ حضرت عبد اللہ بن سائب باب القراءة في الصبح
سورة التكوير
سورۃ انیل
روایت
رض
ترمذی کتاب الصلوة
حضرت عمرو بن حریث باب القراءة في الصلوة الصبح
روایت
مسلم كتاب الصلوة
جمعہ کے دن سورۃ حم السجدۃ اور
رض
حضرت عمرو بن حریث باب القراءة في الصبح
روایت
مسلم کتاب الصلوة
حضرت ابو برزه الاسلمی باب القراءة في الصبح
روایت
رض
ان کا اندازہ ہے کہ فجر کی ہر رکعت
میں 60 سے 100 آیات کی
تلاوت ہوتی تھی.مسلم کتاب الصلوة
نماز فجر میں سورۃ الدھر حضرت ابوہریرۃ" باب القراءة في الصبح
سفر میں
رض
سورۃ الکافرون اور روایت حضرت ابوہریرة مسلم کتاب المسافرين
نماز فجر میں سورۃ الاخلاص
باب استحباب رکعتی سنه
1
Page 10
نماز
نام سورة
روایت
حوالہ
رض
ظہر و عصر پہلی رکعت روایت حضرت جابر بن سمرہ مسلم کتاب الصلوة
سورة النبيل
دوسری رکعت
باب القراءة في الظهر والعصر
دوسری روایت مسلم كتاب الصلوة
رض
سورة الاعلى حضرت جابر بن سمرہ باب القراءة في الصبح
سورۃ الیل و دوسری روایت مسلم کتاب الصلوة
سورة الاعلى حضرت جابر بن سمرہ باب القراءة فى الصبح
مغرب
سورة المرسلات
سوره الطور
روایت
رض
مسلم كتاب الصلوة
حضرت عبداللہ بن عباس باب القراءة في الصبح
روایت
مسلم كتاب الصلوة
حضرت جبیر بن مطعم باب القراءة في الصبح
سورۃ الکافرون.روایت
سورة الاخلاص حضرت جابر بن سمرة
عشاء
سورة التين
روایت
حضرت براء
رض
ابن حجر جلد نمبر 2 صفحہ 248
رض
مسلم کتاب الصلوة
باب القراءة في العشاء
سورة الشمس.ان سورتوں کی حضرت معاذ مسلم كتاب الصلوة
سورۃ ا کی.بن جبل کو مختصر قراءت کی باب القراءة في العشاء
سورۃ السیل.خاطر ہدایت فرمائی.سورۃ الاعلیٰ.سورة البقرة
کا ابتدائی حصہ
2
Page 11
نماز
نام سورة
نماز جمعه و سورۃ الاعلیٰ.روایت
روایت
حوالہ
مسلم كتاب الصلوة
عیدین کے سورة الغاشية حضرت نعمان بن بشیر باب ما يقراء فى صلوة الجمعة
موقع پر
پہلی رکعت میں
روایت
رض
مسلم کتاب الصلوة
سورۃ الجمعہ.حضرت ابوہریرہ باب ما يقراء فى صلوة الجمعة
دوسری رکعت میں
سورة المنافقون
نماز تہجد سورة البقرة - سورة
روایت
بخاری کتاب التهجد
آل عمران اور سورۃ النساء حضرت عائشہ مَنْ عَامَ أَوَّلَ اليل
کی لمبی تلاوت کا ذکر
سورۃ آل عمران کی
آخری دس آیات کی
تلاوت رات کے
تیسرے پہر نماز تہجد
سے قبل
3
بخاری کتاب التفسیر
سورة آل عمران
Page 12
(1)
تلاوت کرتے تھے.-(2)
(3)
تفصیل روایات
{ نماز فجر }
روایت حضرت جابر بن سمرۃ.نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں سورۃ قی کی
(مسلم کتاب الصلاة باب القراءة في الصبح )
روایت حضرت
عبد اللہ بن سائب.سورۃ المومنون کا ابتدائی حصہ.روایت حضرت عمرو بن حریث.سورۃ التکویر.رض
(4).روایت حضرت عمرو بن حریث.سورۃ انیل.(5)
(مسلم کتاب الصلاة باب القراءة في الصبح )
( ترمذی کتاب الصلاة باب القراءة في الصلاة الصبح )
(مسلم کتاب الصلاة باب القراءة في الصلاة الصبح )
روایت حضرت ابو برزہ اسلمی.ان کا اندازہ ہے کہ فجر کی ہر رکعت میں 60 سے
100 آیات کی تلاوت ہوتی تھی.-(6)
رض
(مسلم کتاب الصلاة باب القراءة في الصبح )
روایت حضرت ابوہریرہ.نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز
میں حم السجدۃ اور سورۃ الدھر کی تلاوت فرماتے تھے.-(7)
بھی پڑھی.(مسلم کتاب الصلاة باب القراءة في الصبح )
روایت حضرت ابوہریرہ.سفر میں نماز فجر میں سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص
مسلم کتاب صلاة المسافرين باب استحباب رکعتی سنة )
Page 13
-(1)
{ نماز ظہر و عصر }
نماز ظہر کی پہلی دو رکعتیں آخری دور کعتوں سے تلاوت کے لحاظ سے دوگنی لمبی
ہوتی تھیں.پہلی دورکعتوں میں سے ایک رکعت میں حضرت ابوسعید خدری کا اندازہ قریباً تیس
آیات کے برابر تلاوت کا ہے.حضرت جابر بن سمرہ کے مطابق ظہر وعصر میں سورۃ الیل کی
تلاوت ہوتی تھی.( جس کی اکیس چھوٹی آیات ہیں.دوسری روایت میں سورۃ اعلیٰ کی تلاوت کا بھی
ذکر ہے)
-(2)
روایت حضرت جابر بن سمرة- سورة اليل سورة الاعلى -
مسلم کتاب الصلاۃ باب القراءة في الظهر والعصر )
(مسلم کتاب الصلاة باب القراءة في الصبح)
{ نماز مغرب }
-(1)
روایت حضرت عبداللہ بن عباس.ان کی والدہ ام الفضل نے انہیں مغرب کی
نماز میں سورۃ المرسلات پڑھتے سنا تو کہنے لگیں میرے بیٹے !تم نے نماز مغرب میں یہ سورۃ
تلاوت کر کے مجھے وہ زمانہ یاد کروادیا جب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز مغرب میں سورۃ
المرسلات پڑھتے سنا.-(2)
(مسلم کتاب الصلاة باب القراءة في الصبح)
روایت حضرت جبیر بن مطعم.میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب کی
نماز میں سورۃ الطور پڑھتے سنا.(3)
(مسلم کتاب الصلاة باب القراءة في اصبح)
روایت حضرت جابر بن سمرہ.سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص.جابر
-(1)
{ نماز عشاء }
( ابن حجر جلد 2 صفحہ 248)
حضرت براء بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز عشاء میں
5
Page 14
سورۃ التین کی تلاوت کرتے سنا.-(2)
مسلم کتاب الصلاة باب القراءة في العشاء)
حضرت معاذ بن جبل کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء میں نسبتا مختصر
قراءت کی خاطر سورۃ الشمس والضحیٰ والیل اور سورۃ الاعلی کی تلاوت کی ہدایت
فرمائی.اسی طرح سورۃ البقرۃ کے ابتدائی حصہ تلاوت کا بھی ذکر ملتا ہے.(مسلم کتاب الصلاة باب القراءة في العشاء)
-(1)
{ نماز جمعہ }
روایت حضرت نعمان بن بشیر.نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ اور عیدین کے
(مسلم کتاب الصلاة باب ما يقر آفى صلاة الجمعة )
موقع پر سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیة کی تلاوت فرماتے تھے.-(2)
رض
روایت حضرت ابوہریرۃ.جمعہ کی نماز میں پہلی رکعت میں سورۃ الجمعة
اور دوسری رکعت میں سورۃ المنافقون کی تلاوت کی روایت کا ذکر بھی آیا ہے.حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ
-(1)
نماز
تہجد }
مسلم کتاب الصلاة باب ما يقر افى صلاة الجمعة )
اکثر آدھی رات یا اس سے کم اور
کبھی پوری رات آپ قیام فرماتے اور تلاوت
قرآن کرتے.حضرت عائشہ کے مطابق بعض دفعہ سورۃ البقرۃ آل عمران اور سورۃ
النساء کی لمبی تلاوت کرنے کا ذکر ملتا ہے.جب کوئی عذاب کی آیت آتی تو خدا سے پناہ طلب
کرتے اور جب کوئی رحمت کی آیت آتی تو اس کے لئے دعا کرتے.-(2)
( بخاری کتاب التهجد باب من نام اول الليل )
آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تیسرے پہر تہجد کے لئے بیدار ہوتے تو اٹھتے ہی
نماز تہجد سے قبل سورۃ آل عمران کی آخری دس آیات کی تلاوت فرماتے.( بخاری کتاب التفسير سورة آل عمران )
( بحوالہ خط مکرم حافظ مظفر احمد صاحب، ایڈیشنل ناظر اصلاح وارشاد مقامی محرره 4.2.14)
6
Page 15
نمازوں میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی
تلاوت فرمودہ آیات اور سورتیں
حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اول تو بہت ہی کم نمازوں میں امامت فرمائی ہے.بالعموم
دوسروں
کو نماز پڑھانے کا ارشاد فرمایا کرتے تھے لیکن کبھی کبھی آپ نے بھی امامت فرمائی.نماز
پہلی رکعت دوسری رکعت روایت
حوالہ جات | صفحہ نمبر
فرض میں سورة الاخلاص
روایت
سیرت المہدی
آیت الکرسی
حضرت خواجہ روایت نمبر 520
الم ذلك الكتاب أمَنَ الرَّسُولُ
رض
عبدالرحمن صاحب
روایت
رجسٹر روایات 192...هم المفلحون سے آخر سورت حضرت عبداللہ صحابہ غیر مطبوعہ
رض
تک
تک
صاحب
جلد نمبر 7
مغرب
سورة التين
روایت حضرت رجسٹر روایات
میاں خیر الدین صحابہ غیر مطبوعہ
7
صاحب سیکھوائی جلد نمبر 14
2
Page 16
نماز
پہلی رکعت دوسری رکعت
روایت
حوالہ جات | صفحہ نمبر
مغرب سورۃ یوسف کی وہ
روایت حضرت سیرت المہدی
آیات جن میں یہ
صاحبزاده
روایت نمبر 85
الفاظ آتے ہیں اما
مرزا بشیر احمد
اشْكُوا بَقِي وَ
رض
صاحب
حزني إلى الله
بیان کیا مجھ سے
سورة يوسف
والدہ صاحبہ نے
آیت 87
مغرب
سورة الفلق سورۃ الناس حضرت میاں رجسٹر روایات
رض
عبدالعزیز صاحب صحابہ جلد 9
و
عشاء
مغرب سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص
سورۃ الاخلاص اور اور سورۃ الناس
سورة الفلق
المعروف مغل
سیرت المہدی
روایت نمبر
1108 روایت
37
شیخ کرم الہی
صاحب پٹیالوی
ظہر، دونوں رکعتوں میں سورۃ الفلق روایت حضرت رجسٹر روایات 81،80
عصر،
مغرب
رض
سورۃ الاخلاص اور سورة الناس بابو غلام محمد صاحب صحابہ جلد نمبر 9
سورة الناس
عشاء
8
Page 17
نماز
پہلی رکعت دوسری رکعت
روایت
حوالہ جات صفر نمبر
تہجد دو دو رکعت کر کے سورۃ الاخلاص حضرت ڈاکٹر سیرت المہدی
پڑھتے تھے.پہلی رکعت میں
آیت الکرسی
میر محمد اسماعیل روایت نمبر 32
رض
صاحب
اس کے علاوہ عمومی طور پر علاوہ آیات وفات مسیح کے حسب ذیل آیات آپ کے منہ سے سنی
گئیں.سورة الفاتحة سورة الشمس آيت -10 - سورة الحجرآيت 14 - سورة
الاعراف آیت 157 - سورة التوبة آيت 33 - سورة الاسراء (بنی اسراءیل) آیت
73- سورة النساء آیت 59 سورة الفجر آیت 29 سورۃ الضحی آیت 12 - سورة
الزمر آیت 54 سورة البقرة آیت 156 سورة النساء آیت 148 - سورة طه
آیت 45 - سورة الحجر آیت 43 سورۃ المائدة آیت 68- سورة الجمعة آيت 4
سورۃ البقرۃ آیت 287 سورة البقرة آیت 196 سورۃ العنکبوت آیت 3.سورة النجم آیت 4- سورة النجم آیت 9- سورة الاسراء (بنی اسراءیل) آیت
37 سورة ال عمران آيت 32 سورة البقرة آيت 257- سورة الفرقان
آیت 78
( روایت حضرت ڈاکٹر میر محمد اسمعیل صاحب.بحوالہ سیرت المہدی روایت نمبر 997)
9
Page 18
تفصیل روایات
(1) پہلی رکعت میں آیت الکرسی اور دوسری رکعت میں سورۃ اخلاص
حضرت خواجہ عبدالرحمن صاحب بیان کرتے ہیں.جن دنوں کرم دین والا مقدمہ گورداسپور میں دائر تھا.عموماً حضرت اقدس مقدمہ کی تاریخوں پر
قادیان سے علی الصبح روانہ ہوتے تھے اور نماز فجر راستہ میں ہی حضرت مولوی فضل الدین صاحب
بھیروی کی امامت میں ادا فرماتے تھے.ایک دفعہ بڑاں کی نہر کے قریب نماز فجر کا جو وقت ہوا.تو
حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز فجر کا وقت ہو گیا ہے.یہیں نماز پڑھ لی جائے.اصحاب نے عرض کی کہ حضور حکیم مولوی فضل الدین صاحب آگے نکل گئے ہیں اور خواجہ کمال الدین
صاحب اور مولوی محمد علی صاحب ساتھ ہیں.حضور علیہ الصلاۃ والسلام خاموش ہو گئے اور خود ہی امامت
فرمائی.پہلی رکعت فرض میں آیت الکرسی اور دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص تلاوت فرمائی.“
(سیرت المہدی روایت نمبر 520)
(2) ایک رکعت میں حضور نے سورۃ التین پڑھی
رض
حضرت میاں خیر الدین صاحب سیکھوانی بیان کرتے ہیں.نماز عموما آپ دوسرے کی اقتدا میں پڑھتے تھے.میں نے اس قدر طویل عرصہ میں دو دفعہ حضور کی
اقتدا میں نماز پڑھی.ایک دفعہ قبل دعوی کے مسجد اقصیٰ میں شام کی نماز.ایک رکعت میں حضور نے
سورۃ التین پڑھی تھی.مجھے یاد ہے بڑی دھیمی آواز سے جو بمشکل مقتدی سن سکے اور دوسری دفعہ مولوی
کرم دین والے مقدمہ میں گورداسپور کو جاتے ہوئے بڑی نہر پر ظہر کی نماز حضور کی اقتداء میں پڑھی.“
رجسٹر روایات صحابہ ( غیر مطبوعہ ) جلد 14 صفحہ 2 روایت حضرت میاں خیر الدین صاحب سیکھوانی)
(3) سورۃ یوسف کی آیات
رض
حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب بیان کرتے ہیں.10
Page 19
بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جب کبھی مغرب کی
نماز گھر میں پڑھاتے تھے تو اکثر سورۃ یوسف کی وہ آیات پڑھتے تھے جس میں یہ الفاظ آتے ہیں.إِنَّمَا اشْكُوا بَيني وَحُزْنِي إِلَى اللهِ (يوسف (87) خاکسار عرض کرتا ہے کہ حضرت مسیح موعود کی
آواز میں بہت سوز اور درد تھا اور آپ کی قراءت ہر دار ہوتی تھی.“
(سیرت المہدی روایت نمبر 85)
(4).پہلی رکعت میں الم ذلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ..هُمُ الْمُفْلِحُونَ تك
اور دوسری رکعت میں آمَنَ الرَّسُولُ سے آخر سورۃ تک.حضرت عبد اللہ صاحب ” بیان کرتے ہیں.ایک دفعہ گورداسپور تشریف لے جانے کے وقت صبح کی نماز حضرت صاحب کے پیچھے پڑھی.دار الامان سے باہر کی طرف بطرف گورداسپور ڈھاب کے پاس ایک چھوٹی سی مسجد میں پہلی رکعت
میں حضرت صاحب نے الم ذلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ...هُمُ الْمُفْلِحُونَ تک دوسری
رکعت میں اُمَنَ الرَّسُولُ سے الخ پڑھ کر نماز ادا فرمائی.(رجسٹر روایات صحابه ( غیر مطبوعہ ) جلد 7 صفحہ 192 روایت حضرت عبد اللہ صاحب )
(5) - قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ اور قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ
حضرت میاں عبد العزیز صاحب المعروف مغل کی ایک روایت ہے کہ
ایک دفعہ ایسا اتفاق ہوا ہے کہ حضور نے مسجد مبارک میں نماز پڑھائی.ہم پیچھے تین آدمی تھے.شام
اور عشاء کی دو نمازیں ہم نے حضور کے پیچھے پڑھیں اور دونوں نمازوں میں حضور نے قُلْ أَعُوذُ بِرَبّ
الْفَلَقِ اور قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ایک ایک رکعت میں پڑھا.میں بھی مدت تک ایسا ہی کرتا
رہا.مگر اب چونکہ حضرت خلیفتہ امسیح الثانی شام کی نماز میں سورۃ الفیل اور دوسری رکعت میں قُل اَعُوذُ
برب الناس" پڑھتے ہیں.اور عشاء کی نماز میں واضحی اور والستین پڑھتے ہیں.رض
رجسٹر روایات صحابہ (غیر مطبوعہ ) جلد 9 صفحہ 37 روایت حضرت میاں عبد العزیز صاحب المعروف مغل)
اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ شیخ کرم الہی صاحب پٹیالوی نے بذریعہ تحریر مجھ سے
بیان کیا کہ اپنی بیعت سے قبل میں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تقریر لدھیانہ میں سنی.جب وہ
11
Page 20
تقریر ختم ہوئی تو نماز مغرب ادا کی گئی.امامت حضرت صاحب نے خود فرمائی.اور پہلی رکعت میں
فاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص اور سورۃ الفلق تلاوت فرمائی.اور دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحۃ کے
بعد سورۃ الاخلاص اور قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ" پڑھی.اس کے بعد حضور نے بیعت لی.اس روز
ہم دو آدمیوں نے بیعت کی تھی.“
(سیرت المہدی روایت نمبر 1108)
(6) - قُلْ هُوَ اللهُ أَحَد اور قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ
رض
حضرت بابو غلام محمد صاحب بیان کرتے ہیں.مولوی عبد الکریم صاحب سر درد اور بخار کے سبب سے صاحب فراش ہو گئے.ادھر شاہ دین
سٹیشن ماسٹر بھی بخار میں مبتلا تھے.حضور مجلس میں نماز کے لئے تشریف لائے.کچھ دیر بیٹھنے کے بعد
آپ نے فرمایا کہ مولوی صاحب کا کیا حال ہے؟ ایک آدمی نے اٹھ کر مولوی صاحب سے دریافت
کیا.آپ نے جواب دیا دس دے کہ بخار بھی ہے اور سر درد بھی ہے.پھر انتظار کے بعد حضور
نے فرمایا کہ پوچھو نماز پڑھائیں گے؟ مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضور مجھ سے تو اٹھا بھی نہیں
جاتا.اب ظہر کو دیر ہورہی تھی کہ حضور (سے) کہنے لگے.حضور خواجہ صاحب ، محمد علی اور حکیم فضل دین
صاحب موجود ہیں کیا وہ نماز پڑھا دیں؟ اکثر کا نام لیا گیا مگر حضور خاموش بیٹھے رہے.کچھ انتظار کے
بعد حضور خود مصلیٰ پر تشریف فرما ہوئے اور ظہر پڑھائی.ہم سب نے حضور کی اقتدا میں نماز ادا کی.بہت ہی ہلکی نماز تھی.سجدے بھی ہلکے تھے.اسی طرح عصر کے وقت بھی حضور خود کھڑے ہوئے اور
عصر بھی حضور نے پڑھائی.مغرب کی نماز بھی حضور نے ہی پڑھائی.دونوں رکعتوں میں حضور نے
قُلْ هُوَ الله احد اور قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ يَا قُل اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ پڑھی تھیں حتی کہ عشاء
بھی انہی ہلکی ہلکی سورتوں کے ساتھ پڑھائی.“
(رجسٹر روایات صحابہ ( غیر مطبوعہ ) جلد 9 صفحہ 80، 81 روایت حضرت با بو غلام محمد صاحب)
(7).پہلی رکعت میں آیت الکرسی اور دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص
رض
حضرت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے بیان کیا کہ
1895ء میں مجھے تمام ماہ رمضان قادیان میں گزارنے کا اتفاق ہوا اور میں نے تمام مہینہ
حضرت صاحب کے پیچھے نماز تہجد یعنی تراویح ادا کی.آپ کی یہ عادت تھی کہ وتر اول شب میں پڑھ لیتے
12
Page 21
تھے اور نماز تہجد آٹھ رکعت دو دو کر کے آخر شب میں ادا فرماتے تھے.جس میں آپ ہمیشہ پہلی
رکعت میں آیت الکرسی تلاوت فرماتے تھے.یعنی اللہ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
تک اور دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص کی قراءت فرماتے تھے اور رکوع اور سجود میں یاحی
يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِيثُ اکثر پڑھتے تھے اور ایسی آواز سے پڑھتے تھے کہ آپ کی آواز میں
سن سکتا تھا.“
(سیرت المہدی روایت نمبر 320)
(8).بعض آیات آپ خصوصیت کے ساتھ زیادہ پڑھا کرتے تھے
( غالباً یہ نماز کے دوران کی بات نہیں بلکہ عمومی گفتگو کی بات ہوگی.)
رض
حضرت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے بیان کیا کہ
حضرت مسیح موعود علیہ السلام یوں تو ہر امر میں قرآن مجید کی طرف رجوع کرتے تھے مگر بعض
بعض آیات آپ خصوصیت کے ساتھ زیادہ پڑھا کرتے تھے.علاوہ وفات مسیح کی آیات کے
حسب ذیل آیات آپ کے منہ سے زیادہ سنی ہیں.سورة الفاتحه قد أَفْلَحَ مَن زَتْهَا الشمس (10) إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَكُمْ (الحجرات
(14) رحمتى وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ (الاعراف (157) هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْهُدَى وَدِيْنِ الْحَقِّ
لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ (التوبة (33) مَنْ كَانَ فِي هذة أعمى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمى (بنی اسراءيل
(73) إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَ بِالسُّوءِ (يوسف (54) يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبَّكِ رَاضِيَةً
مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبدِي وَادْخُلِي جَنَّتِي (الفجر 8 تا 31 ) وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَيثُ (الضحى 12)
قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا
(الزمر (54) وَبيَّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ
أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلوتٌ مِّن رَّيْهِم وَ رَحْمَةٌ (البقرة 156 تا 158 ) مَا يَفْعَلُ اللهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ
شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ (النساء (148) فَقُوْلَا لَهُ قَوْلًا لَّيْنًا (طه 45) إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ
سُلْطَان (الحجر 43) وَ اللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ (المائدة (68) وَأَخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ
(الجمعة (4) لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا (البقرة (287) وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ
13
Page 22
(البقرة 196) أحَسِبَ النَّاسُ أَن يَتَرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ (العنكبوت (3)
مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ إِلَّا وَحْى يُوحَى (النجم (5.4) ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ
ادنى (النجم 10,9) لا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ (بنی اسراءيل (37) قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ
فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ (ال عمران (32) لا إكراه في الدين (البقرة 257) قُلْ مَا يَعْبَوابِكُمْ رَبِّي
لوْلَا دُعَاؤُكُمُ (الفرقان 78)
(سیرت المہدی روایت نمبر 997)
( بحوالہ خط مکرم سید مبشر یا از صاحب.ریسرچ سیل محرره 16.2.14)
14
Page 23
نمازوں میں حضرت خلیفہ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کی تلاوت فرمودہ آیات اور سورتیں
نماز
سورة
حوالہ
سورة البروج
حیات نور صفحہ 374
تفصیل روایت
سید نا حضرت خلیفتہ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق روایات کی کمی تھی.زبانی روایت
نا
کر سکنے والے بزرگ اب موجود نہیں اور تحریر میں سے فی الحال صرف ایک حوالہ حیاتِ نور سے مل
سکا ہے.فجر کی نماز کے لئے لوگ مسجد مبارک میں حضرت
خلیفہ المسیح الاول کا انتظار کر رہے تھے.آخر حضور تشریف لے آئے اور حضور کا تشریف لانا تھا کہ مسجد میں ایک سناٹا چھا گیا.نماز شروع
ہوئی.حضور نے نماز میں سورۃ البروج کی تلاوت فرمائی.گو وہ ساری کی ساری سوز و گداز اور خشوع و
خضوع کا مجموعہ تھی مگر جب حضور نے آیت اِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ
لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ پڑھی تو اس کے بعد کی کیفیت
حضرت خلیفۃ المسیح الثانی ایدہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ میں یوں ہے کہ اس وقت تمام جماعت کا عجیب
حال ہو گیا.یوں معلوم ہوتا تھا کہ گویا یہ آیت اسی وقت نازل ہوئی ہے اور ہر ایک شخص کا دل
خشیت اللہ سے بھر گیا.“
( حواله از کتاب حیات نور صفحہ 374.ایڈیشن دوم.مصنف عبد القادر سابق سودا گریل - مطبع ضیاء الاسلام پریس ربوہ )
15
Page 24
نمازوں میں حضرت
خلیفہ المسیح الثانی رضی اللہ تعالی عنہ کی
نماز
تلاوت فرمودہ آیات اور سورتیں
پہلی رکعت دوسری رکعت روایت
جمعه و سورة الاعلى سورة الغاشية روایت مكرم محترم سید
عیدین
میر محموداحمد ناصر صاحب
رتن باغ سورة الدهر سورة القيامة روایت مکرم محترم سید
میں نماز
پڑھاتے
ہوتے
میر محموداحمد ناصر صاحب
حوالہ
صفحہ نمبر
مغرب روزانہ ایک
روایت مکرم محترم سید
رکعت میں
میر محمود احمد ناصر صاحب
سورة الفيل
تلاوت
فرماتے تھے
مغرب سورة الفيل سورة الناس روایت حضرت میاں رجسٹر روایات
عشاء
رض
صحابہ جلد 9
عبد العزیز صاحب سیرت المهدی
(المعروف مغل) بحوالہ خط سید مبشر
سورة الضحى سورة التين روایت حضرت میاں
ایاز صاحب
رض
عبدالعزیز صاحب
16
40
37
37
Page 25
نماز
پہلی رکعت دوسری رکعت
روایت
حوالہ
صفحہ نمبر
بحوالہ خط ملرم
فجر
سورة الغاشية دیگر سورتیں
روایت صاحبزاده
ناصر احمد مس
مرزا خورشید احمد صاحب
صاحب
فجر
مغرب
مغرب
سورة الاعلى سورة الغاشية روایت سید قمر سليمان صاحب
( بزرگوں سے سنا ہے )
سورة الفيل سورة الناس روایت حضرت مصلح موعود حوالہ انوار العلوم
تقریر فرموده 26 مئی جلد نمبر 14
صفحہ 10
1935ء بمقام قادیان
سورة الفيل سورة الناس روایت صاحبزاده بحوالہ خط مکرم
مرزا خورشید احمد صاحب ناصر احمد شمس
مغرب
عشاء
سورة الفيل سورة الناس روایت سید قمر سلیمان صاحب
( بزرگوں سے سنا ہے )
سورة الضحى سورة التين روایت سید قمر سلیمان صاحب
( بزرگوں سے سنا ہے )
نماز جمعہ سورۃ الاعلیٰ سورة الغاشية روایت صاحبزاده
مرزا خورشید احمد صاحب
نماز جمعہ سورۃ الاعلى سورة الغاشية روایت سید قمر سليمان صاحب
( بزرگوں سے سنا ہے )
17
Page 26
تفصیل روایات
حضرت خلیفتہ المسیح الثانی شام کی نماز میں سورۃ الفیل اور دوسری رکعت میں قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ
النامیں پڑھتے ہیں اور عشاء کی نماز میں سورۃ الضحی اور سورۃ التین پڑھتے ہیں.(رجسٹر روایات صحابہ جلد 9 صفحہ 37 روایت حضرت میاں عبد العزیز صاحب المعروف مغل)
( بحوالہ خط سید مبشر ایاز صاحب محرره 16.2.14)
حضرت مصلح موعود نماز جمعہ اور عیدین میں باقاعدگی سے سورۃ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأخلی اور
سورة هل أتك حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ تلاوت فرماتے تھے.البتہ لاہور رتن باغ میں ایک دفعہ سورۃ
الدھر اور سورۃ القیامۃ بھی تلاوت فرمائی.روزانہ مغرب کی نماز پڑھاتے ہوئے ایک رکعت میں
سورۃ الفیل تلاوت فرماتے تھے.( روایت بحوالہ خط مکرم محترم سید میرمحمود احمد ناصر صاحب محرره 3.2.14)
حضرت مصلح موعود اپنی تقریر فرمودہ 26 مئی 1935ء بمقام قادیان فرماتے ہیں.جنگ عظیم کے زمانہ میں جب لڑکی لڑائی میں شامل ہوا اور بعض حکومتوں نے تجویز کیا کہ عرب
پر حملہ کیا جائے تو یہ خبر سنتے ہی میں نے مغرب کی نماز میں سورۃ الفیل اس لئے پڑھنی شروع کر دی کہ
خدا تعالیٰ مکہ کو دشمنوں کے حملہ سے بچائے.آج اس پر بیس سال کے قریب گزر چکے ہیں اور میں
بغیر ایک ناغہ کے یہ دعا کرتا رہا ہوں.“
محترم صاحبزادہ مرزا خورشید احمد صاحب کی روایت کے مطابق حضرت مصلح موعود مغرب کی نماز
میں سورۃ الفیل اور سورۃ الناس کی تلاوت فرماتے.نماز جمعہ میں سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیۃ اور نماز
فجر میں سورۃ الغاشیۃ اور دیگر مختلف سورتیں پڑھتے تھے.مکرم سید قمر سلیمان صاحب بیان کرتے ہیں کہ بزرگوں سے سنتے آئے ہیں کہ حضور فجر کی نماز اور
نماز جمعہ میں سورۃ الغاشیۃ اور سورۃ الاعلیٰ.نماز مغرب میں سورۃ الفیل اور سورۃ الناس جب کہ نما ز عشاء
میں سورۃ الضحی اور سورۃ التین کی تلاوت فرماتے.روایت بحوالہ خط مکرم ناصر حمد شمس صاحب ، سیکرٹری فضل عمر فاؤنڈیشن - محررہ 22.10.14)
18
Page 27
نمازوں میں حضرت
خلیفہ المسیح الثالث
رحمہ اللہ تعالی
کی تلاوت فرمودہ آیات اور سورتیں
نماز
پہلی رکعت دوسری رکعت
روایت
فجر
سترہ آیات کی دونوں رکعات میں تلاوت بروایت مکرم حضرت صاحبزادہ مرزا خورشید احمد صاحب
ناظر اعلی و امیر مقامی
سورة القيامة
سورۃ الدھر
بروایت مکرم چوہدری حمید اللہ صاحب.مکرم مرزا محمد الدین ناز صاحب
سورۃ البقرۃ کی دوسرا رکوع سترہ آیات بروایت مکرم صاحبزادہ مرزا غلام احمد صاحب
ستره آیات
کا بقیہ حصہ
مکرم حافظ مظفر احمد صاحب
سورۃ البقرۃ کی سترہ
بروایت مکرم منیر احمد بسمل صاحب
ابتدائی آیات
کبھی سورۃ الدھر
سورۃ البقرۃ کی
سترہ آیات دونوں
بروایت مکرم انجینئر محمود مجیب اصغر صاحب
رکعتوں میں
سورة البقرة كا سورۃ البقرۃ کی آیت بروایت مکرم انجینر محمود مجیب اصغر صاحب
پہلار کوع
نمبر 287 پڑھتے تھے
مغرب تینوں قل والی سورتیں
بروایت مکرم حضرت صاحبزادہ مرزا خورشید احمد صاحب
ناظر اعلی و امیر مقامی
19
Page 28
نماز
پہلی رکعت
دوسری رکعت
سورة الاخلاص والفلق سورۃ الناس
روایت
بروایت مکرم چوہدری حمید اللہ صاحب.مکرم میرمحموداحمد ناصر صاحب ،کرم مبشر احمد کاہلوں
صاحب مکرم منیر احمد بسمل صاحب.مکرم حافظ مظفر احمد صاحب.مکرم انجینئر محمود مجیب اصغر صاحب
سورۃ الناس بروایت مکرم انجینئر محمود مجیب اصغر صاحب
مغرب
پہلی رکعت میں
سورة الفيل
عشاء
سورة الضحى
سورة الانشراح
بروایت را ناتصور احمد خان صاحب.مکرم انجینئر محمودمجیب اصغر صاحب
بروایت را ناتصور احمد خان صاحب
سورة التين کوئی دوسری آیت
سورة الضحى سورة الانشراح بروایت مکرم انجینئر محمود مجیب اصغر صاحب
آیت الکرسی سورة الحشر رکوع نمبر 3
جمعہ
سورۃ الاعلیٰ
سورة الغاشية
"
//
بروایت مکرم مبشر احمد کاہلوں صاحب،
مکرم مرز امحمد الدین نازصاحب،
مکرم حافظ مظفر احمد صاحب
مکرم انجینئر محمود مجیب اصغر صاحب
20
20
Page 29
تفصیل روایات
جہاں تک مجھے یاد ہے فجر کی نماز میں سترہ آیات کی ( دونوں رکعات میں) کئی دفعہ تلاوت فرمایا کرتے
تھے.اسی طرح ایک زمانہ میں مغرب کی نماز میں بہت دفعہ تینوں قل والی سورتیں بھی تلاوت فرماتے تھے.( روایت جوال خلط مکرم محترم مرزا خورشید احمد صاحب.ناظر علی و امیر مقامی محر ر 8.1.14)
لہ
مغرب کی نماز کی پہلی رکعت میں حضرت خلیفتہ امسیح الثالث ہمیشہ سورۃ الاخلاص اور سورۃ الفلق
دونوں اکٹھی پڑھتے تھے اور دوسری رکعت میں ہمیشہ سورۃ الناس تلاوت کرتے تھے ( بلا ناغہ ).( بحوالہ خط مکرم محترم مبشر احمد کاہلوں صاحب - محررہ 16.1.14)
میری یادداشت کے مطابق حضرت صاحب فجر کی پہلی رکعت میں سورۃ البقرۃ کا پہلا رکوع اور
دوسری رکعت میں سورۃ البقرۃ کی آیات 9 تا 17 بھی تلاوت فرماتے رہے.اسی طرح نماز مغرب
کی پہلی رکعت میں سورۃ الاخلاص اور الفلق ، دوسری میں سورۃ الناس.نماز جمعہ میں سورۃ الاعلی اور
دوسری رکعت میں سورۃ الغاشية تلاوت فرماتے تھے.-(1)
-(2)
(3)
(4)
( بحوالہ خط مکرم محترم حافظ مظفر احمد صاحب، محرره 4.2.14)
نماز فجر }
نماز فجر کی پہلی رکعت میں سورۃ القیامۃ اور دوسری رکعت میں سورۃ الدھر.روایت مکرم چوہدری حمید اللہ صاحب.مکرم مرزا محمد الدین ناز صاحب )
سورة البقرة کی پہلی سترہ آیات.پہلی رکعت میں پہلا رکوع اور دوسری رکعت میں باقی حصہ.( روایت مکرم مرزا غلام احمد صاحب)
نماز مغرب }
نماز مغرب کی پہلی رکعت میں سورۃ الاخلاص اور الفلق ، دوسری رکعت میں سورۃ الناس.روایت مکرم چوہدری حمید اللہ صاحب - مکرم مبشر احمد کا بہلوں صاحب.مکرم سید میر محمود احمد ناصر صاحب)
{ نماز عشاء}
عشاء میں سورۃ الضحی اور سورۃ الانشراح اور بعض اوقات سورۃ التین اور دوسری کوئی سورۃ.روایت مکرم را نا تصور احمد خان صاحب)
21
Page 30
(5)
{ نماز جمعہ}
نماز جمعہ میں سورۃ الاعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیۃ تلاوت فرماتے تھے.( روایت مکرم مبشر احمد کاہلوں صاحب مکرم مرزا محمد الدین ناز صاحب )
روایات بحوالہ خط مکرم حافظ مظفر احمد صاحب.ایڈیشنل ناظر اصلاح و ارشاد مقامی - محرره 4.2.14)
جہاں تک خاکسار کو یاد ہے حضور رحمہ اللہ صبح کی نماز میں سورۃ البقرۃ کی سترہ ابتدائی آیات اور
کبھی سورۃ الدھر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے.اسی طرح مغرب کی نماز میں پہلی رکعت میں سورۃ
قُلْ هُوَ الله احد اور قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ اور دوسری رکعت میں قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ
کی تلاوت فرمایا کرتے تھے.( روایت بحوالہ خط مکرم منیر احمد بسمل صاحب - محرر 9.1.14)
جہاں تک خاکسار کی یادداشت کا تعلق ہے.اس سلسلے میں عرض ہے کہ جمعہ اور عیدین پر بھی
حضور سورۃ فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیة کی تلاوت
کرتے تھے.مغرب میں عموماً حضرت مصلح موعود کی طرح سورۃ الفیل اور سورۃ الناس پڑھتے تھے.خاکسار کو یاد ہے اسلام آباد میں بعض اوقات مغرب کی پہلی رکعت میں سورۃ الاخلاص اور سورۃ الفلق
اور دوسری رکعت میں سورۃ الناس کی تلاوت کرتے تھے.ابتداء میں ہی آپ نے سورۃ البقرۃ کی پہلی
ستره آیات یاد کرنے کی تحریک فرمائی تھی اور فجر کی نماز میں بعض اوقات دونوں رکعتوں میں
سورۃ البقرۃ کی سترہ آیات پڑھتے تھے ( دو حصوں میں ).بعض اوقات فجر میں سورۃ البقرۃ کا پہلار کوع
اور دوسری رکعت میں سورۃ البقرۃ کی آخری آیت بھی آیت نمبر 287.عشاء کی نماز میں سورۃ الضحی
اور سورۃ الم نشرح بعض اوقات پڑھتے تھے.جہاں تک خاکسار کو یاد پڑتا ہے کہ حضور بدل بدل
کر آیات یا رکوع یا سورتیں تلاوت کرتے تھے.کئی دفعہ آیت الکرسی والا رکوع سورة الحشر والا رکوع
نمبر 3 بھی پڑھتے تھے.( روایت بحوالہ خط مکرم انجینئر محمود مجیب اصغر صاحب - محرره 23.1.14)
22
Page 31
تفصیل روایات
سیدنا حضرت خلیفہ امسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بصرہ العزیز کے زیر ہدایت دفتر پرائیویٹ
سیکرٹری لندن سے جو تفصیل حضرت خلیفتہ امسیح الرابع کی تلاوت فرمودہ آیات وشور کے بارہ میں
موصول ہوئی ہے اُسے ایڈیشن ھذا ( دوم ) میں شامل کیا جا رہا ہے.نمازوں میں حضرت خلیفتہ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالی
کی تلاوت فرمودہ آیات اور سورتیں
نماز فجر میں تلاوت قرآن کریم
پہلی رکعت
جمعتہ المبارک بنی اسرائیل: آیات 79 تا 85
ہفتہ
اتوار
پیر
سورة الكهف 103 تا 107
سورة الرعد 9 تا 14
سورة البروج (مکمل)
منگل سورۃ البقرۃ: پہلار کوع آیات 1 تا 8
بدھ
سورة البقرة آخری رکوع
جمعرات سورۃ الانعام آیت 96 تا101
دوسری رکعت
سورة الكهف 1 تا 13
سورة الكهف : 108 تا 111
سورة الملک : 1 تا 5
سورة الطارق (مکمل)
سورة البقرة : آيات 9 تا 17
سورة ال عمران : آیات 191 تا 195
سورة الانعام : آیات 102 تا 109
23
23
Page 32
تاریخ
20
20
14
8
2
اتوار
جمعرات
بدھ
دوسری رکعت سورة العصر
تلاوت برائے نماز مغرب برائے نماز عشاء
26 پہلی رکعت سورة الانشراح
پہلی رکعت سورة النحل آيات 67 تا71
سورة الاحزاب آيات 70 تا 74
دوسری رکعت
21
15
9
3
221
27 : پہلی رکعت سورة الفيل
پہلی رکعت سورة الضحى
سوموار
اتوار
ہفتہ
جمعہ
دوسری رکعت سورة القريش
دوسری رکعت سورة التين
22
16
10
4
28 : پہلی رکعت سورة الزلزال
پہلی رکعت آیت الکرسی ( سورة البقره آیت
منگل
سوموار
اتوار
ہفتہ
جمعہ
دوسری رکعت سورة النصر
نمبر 256)
23
17
11
5
29 پہلی رکعت سورة الْقَارِعَةُ
منگل
بدھ
سوموار
اتوار
ہفتہ
دوسری رکعت سورة التكاثر
دوسری رکعت سورۃ آل عمران آیات 26 تا 28
پہلی رکعت سورة الحشرآيات 19 تا22
دوسری رکعت سورة الحشرآيات 23-25
60
24
18
12
جمعرات
بدھ
منگل
سوموار
30 : پہلی رکعت سورة الهمزة
اتوار دوسری رکعت سورة الماعون
پہلی رکعت
سورة حم السجدة آيات 31 تا 33
دوسری رکعت سورة حم السجدة آيات 34 تا
25
19
13
7
جمعہ
حرات
بدھ
24
24
رف له
36
31 پہلی رکعت سورة الكافرون
سوموار : دوسری رکعت سورة الاخلاص
پہلی رکعت سورة الفلق
دوسری رکعت سورة الناس
Page 33
نمازوں میں حضرت خلیفہ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز
کی تلاوت فرمودہ آیات اور سورتیں
دن
نماز
جمعہ
پہلی رکعت
دوسری رکعت
سورۃ ( بنی اسرائیل ) الاسراء سورۃ الکہف آیات 1 تا 11
آیات 79 تا 85
مغرب
سورة الفيل
عشاء
سورة الضحى
سورة القريش
سورة التين
ہفتہ
سورة البقرة آيات 1 تا 8 سورة البقرة آيات 9 تا 17
مغرب
عشاء
سورة الفلق
آیت الکرسی
سورة الناس
سورة البقرة آخرى آیت
اتوار
مغرب
سورة الفلق
عشاء
سوموار
مغرب
عشاء
منگل
سورة الكهف آیات 103 تا 107 سورۃ الکہف آیات 108 تا 111
سورۃ الناس
سورة حم السجدة آيات 31 تا 33 سورة حم السجدة آيات 34 تا 37
سورة البقرة آیات 285 تا 287 سورۃ آل عمران آیات 191 تا 195
سورة الفلق
سورة الناس
سورة الحشر آيات 19 تا 22 سورة الحشر آيات 23 تا 25
سورة البقرة آيات 255 تا 258 سورۃ آل عمران آیات 26 تا 31
مغرب
سورة الكافرون
سورة النصر
عشاء
سورۃ الزلزال
سورة التكاثر
25
25
Page 34
دن
نماز
بدھ
پہلی رکعت
دوسری رکعت
سورة الكهف آیات 103 تا 107 سورۃ الکہف آیات 108 تا 111
مغرب
عشاء
سورة اللهب
سورة الشمس
سورۃ الاخلاص
سورة الضحى
جمعرات
سورة البقرة آيات 285 تا 287 سورۃ آل عمران 191 تا 195
مغرب
سورة الفلق
سورۃ الناس
عشاء
سورة الضحية
سورۃ الم نشرح
26
20
Page 35
XXXXXXXXXXXXXXXX
سورة الفاتحه
***************
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الـ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ
الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
مُلِكِ يَوْمِ الدِّينِ
ايَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ
1 - ( میں ) اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا
(اور) بار بار رحم کرنے والا ہے (پڑھتا ہوں ).2.ہر قسم کی) تعریف کا اللہ (ہی) مستحق ہے
( جو ) تمام جہانوں کا رب ( ہے ).3.بے حد کرم کرنے والا.بار بار رحم کرنے والا.4.( اور ) جزا سزا کے وقت کا مالک ہے.5.(اے خدا ) ! ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور
تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں.اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ )
6.ہمیں سیدھے راستے پر چلا.صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمُ : 7- ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا
غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ہے.جن پر نہ تو تیرا ( بعد ) میں غضب نازل ہوا
( ہے ) اور نہ وہ ( بعد میں ) گمراہ ( ہو گئے ) ہیں.27
Page 36
حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں:
ترجمہ: خدا جس کا نام اللہ ہے تمام اقسام تعریفوں کا مستحق ہے.اور ہر ایک تعریف اسی کی شان
کے لائق ہے کیونکہ وہ رب العالمین ہے.وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ مالک یوم الدین ہے.ہم
(اے صفات کاملہ والے) تیری ہی پرستش کرتے ہیں اور مدد بھی تجھ سے ہی چاہتے ہیں.ہمیں وہ
سیدھی راہ دکھلا جو ان لوگوں کی راہ ہے جن پر تیرا انعام ہے.اور ان راہوں سے بچا جوان لوگوں کی راہیں
ہیں جن پر تیرا غضب طاعون وغیرہ عذابوں سے دنیا ہی میں وارد ہوا اور نیز ان لوگوں کی راہوں سے بچا
کہ جن پر اگرچہ دنیا میں کوئی عذاب وارد نہیں ہوا.مگر اخروی نجات کی راہ سے وہ دور جا پڑے ہیں اور
آخر عذاب میں گرفتار ہوں گے.ایام الصلح.روحانی خزائن جلد 14 صفحہ 246)
جاننا چاہئے کہ سورۃ فاتحہ کے بہت سے نام ہیں جن میں سے پہلا نام فاتحه
الکتاب ہے اور اس کا یہ نام اس لئے رکھا گیا ہے کہ قرآن مجید اسی سورۃ سے شروع ہوتا
ہے.نماز میں بھی پہلے یہی سورۃ پڑھی جاتی ہے اور خدا تعالیٰ سے جورب الارباب ہے
دُعا کرتے وقت اسی ( سورۃ ) سے ابتدا کی جاتی ہے.اور میرے نزدیک اس سورۃ کو
فاتحہ اس لئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اِس سورۃ کو قرآن کریم کے مضامین کے لئے حکم
قرار دیا ہے.اور جو اخبار غیبیہ اور حقائق و معارف قرآن مجید میں احسان کرنے والے خدا کی
طرف سے بیان کئے گئے ہیں وہ سب اس میں بھر دیے گئے ہیں.اور جن امور کا انسان کو
مبدء ومعاد ( دنیا اور آخرت) کے سلسلہ میں جاننا ضروری ہے، وہ سب اس میں موجود ہیں.مثلاً وجود باری ، ضرورت نبوت اور مومن بندوں میں سلسلہ خلافت کے قیام پر استدلال.اور اس سورۃ کی سب سے بڑی اور اہم خبر یہ ہے کہ یہ سورۃ مسیح موعود اور مہدی معہود کے
28
Page 37
زمانہ کی بشارت دیتی ہے....اسی طرح اس سورۃ میں بیان شدہ خبروں میں سے ایک خبر یہ بھی
ہے کہ یہ سورۃ اس دنیا کی عمر بتاتی ہے....یہ وہی سورۃ فاتحہ ہے جس کی خبر خدا تعالیٰ کے انبیاء
میں سے ایک نبی نے دی.اس نبی نے کہا کہ میں نے ایک قوی فرشتہ دیکھا جو آسمان سے
اترا، اس کے ہاتھ میں سورۃ فاتحہ ایک چھوٹی سی کتاب کی شکل میں تھی اور خدائے قادر کے حکم
سے اس کا دایاں پاؤں سمندر پر اور بایاں پاؤں خشکی پر پڑا اور وہ شیر کے غرانے کی مانند بلند
آواز میں پکارا، اس کی آواز سے سات گرجیں پیدا ہوئیں جن میں سے ہر ایک میں ایک مخصوص
کلام (جملہ ) سنائی دیا اور کہا گیا کہ ان گرجوں میں سے پیدا ہونے والے کلمات کو سر بمہر
کردے اور انہیں مت لکھ.خدائے مہربان نے ایسا ہی فرمایا ہے اور نازل ہونے والے
فرشتہ نے اس زندہ خدا کی قسم کھا کر جس کے نور نے سمندروں اور آبادیوں کو روشن کیا ہے
کہا کہ اس ( مسیح موعود ) کے زمانہ کے بعد اس شان و مرتبہ کا زمانہ نہ آئے گا.اور
مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ پیشگوئی مسیح موعود کے زمانہ سے متعلق ہے.سو
اب وہ زمانہ آ گیا ہے اور سورۃ فاتحہ کی سات آیات سے وہ سات آواز میں ظاہر ہوگئی ہیں اور یہ
زمانہ نیکی اور ہدایت کے لحاظ سے آخری زمانہ ہے اور اس کے بعد کوئی زمانہ اس زمانہ کی
شان و مرتبہ کا نہیں آئے گا اور جب ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو پھر ہمارے بعد
قیامت تک کوئی اور مسیح نہیں آئے گا اور نہ ہی کوئی آسمان سے اترے گا اور نہ ہی کوئی غار سے
نکلے گا.سوائے اس موعود لڑکے کے جس کے بارہ میں پہلے سے میرے رب کے کلام میں ذکر
آچکا ہے.یہی بات سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ( مسیح موعود ) آنے والا تھا وہ
آگیا ہے اور زمین و آسمان اس پر گواہی دے رہے ہیں.اعجاز مسیح روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 70-73)
سورۃ فاتحہ کے اور نام بھی ہیں جن میں سے ایک سُورَةُ الحمد بھی ہے کیونکہ یہ سورۃ
ہمارے رب اعلیٰ کی حمد سے شروع ہوتی ہے.اور سورۃ فاتحہ کا ایک نام اُم القرآن بھی ہے کیونکہ وہ تمام قرآنی مطالب پر احسن پیرایہ
29
Page 38
میں حاوی ہے اور اس نے سیپ کی طرح قرآن کریم کے جواہرات اور موتیوں کو اپنے اندرلیا
ہوا ہے.اور یہ سورۃ علم و عرفان کے پرندوں کے لئے گھونسلوں کی مانند بن گئی ہے.یادر ہے
که قرآن کریم میں انسانوں کی رہنمائی کے لئے چار مضامین بیان کئے گئے ہیں.1.علم مبدء.2 علم معاد - 3 علم نبوت.4 علم تو حید ذات وصفات.اور لاریب یہ چاروں علوم سورۃ فاتحہ
میں موجود ہیں.اور یہ علوم اکثر علمائے امت کے سینوں میں زندہ درگور کی حیثیت رکھتے ہیں،
کیونکہ وہ لوگ سورۃ فاتحہ کو پڑھتے تو ہیں لیکن وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتی اور وہ اس کی ان
سات نہروں کو پوری طرح جاری نہیں کرتے ( تا وہ خود بھی اور دوسرے لوگ بھی ان سے فائدہ
اٹھائیں بلکہ وہ فاجر لوگوں کی سی زندگی بسر کرتے ہیں.اس کا نام اُٹھ الکتاب بھی ہے کیونکہ قرآن شریف کی تمام تعلیم کا اس میں خلاصہ اور
عطر موجود ہے.سورۃ کا نام ام الکتاب رکھنے کی یہ وجہ بھی ہوسکتی ہے کہ امور روحانیہ کے بارے میں
اس میں کامل تعلیم موجود ہے، کیونکہ سالکوں کا سلوک اُس وقت تک پورا نہیں ہوتا جب تک
کہ اُن کے دلوں پر ربوبیت کی عزت اور عبودیت کی ذلت غالب نہ آ جائے.اس امر میں
خدائے واحد ویگانہ کی طرف سے نازل شدہ سورۃ فاتحہ جیسا رہنما اور کہیں نہیں پاؤ گے.کیا تم دیکھتے
نہیں کہ اس نے کس طرح الْحَمدُ لله رب العلمین سے لے کر مُلِكِ يَوْمِ الدِّينِ تک کے
الفاظ سے اللہ تعالیٰ کی عزت اور عظمت کو ظاہر فرمایا ہے.پھر اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ
کہہ کر بندہ کے عجز اور کمزوری کو ظاہر کیا ہے.پھر یہ بھی ممکن ہے کہ اس سورۃ کو اُٹھ الکتاب اس امر کے پیش نظر کہا گیا ہو کہ اس میں
انسانی فطرت کی سب ضرورتیں مڈ نظر ہیں اور انسانی طبائع کے سب تقاضوں کی طرف اشارہ
ہے خواہ وہ کسب سے متعلق ہوں یا افضال الہیہ سے.کیونکہ انسان اپنے نفس کی تعمیل کے لئے
اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات اور افعال کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے.اور یہ بھی چاہتا ہے کہ اسے
اس کے ان احکام کے وسیلہ سے اس کی خوشنودی کا علم ہو جائے ، جن کی حقیقت اس کے
30
Page 39
اقوال سے ہی کھلتی ہے اور ایسا ہی اس کی روحانیت چاہتی ہے کہ عنایت ربانی اس کی دستگیری
کرے اور اس کی مدد سے اسے صفاء باطن اور انوار و مکاشفات الہیہ حاصل ہوں اور یہ سورۃ
کریمہ ان سب مطالب پر مشتمل ہے بلکہ یہ سورۃ اپنے حسنِ بیان اور قوت تبیان سے دلوں کو
موہ لینے والی ہے.م اس سورۃ کے ناموں میں سے ایک نام سبع مقانی ہے اور اس نام کی وجہ تسمیہ یہ ہے
کہ اس سورۃ کے دو حصے ہیں.اس کا ایک حصہ بندہ کی طرف سے خدا کی ثنا اور دوسرا نصف فانی
انسان کے لئے خدا تعالیٰ کی عطا اور خش پر مشتمل ہے.بعض علماء کے نزدیک اس کا نام السَّبُعُ الْمَتَانی اس لئے ہے کہ یہ سورۃ تمام كُتب الہیہ
میں امتیازی شان رکھتی ہے اور اس کی مانند کوئی سورۃ تورات یا انجیل یا دوسرے صحفِ انبیاء
میں نہیں پائی جاتی.اور بعض کا خیال ہے کہ اس کا نام مثانی اس لئے ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی ایسی
سات آیات پر مشتمل ہے کہ ان میں سے ہر آیت کی قراءت قرآنِ عظیم کے ساتویں حصہ کی
قراءت کے برابر ہے.اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس
کا نام السَّبْعُ الْمَقَانِع اس بنا پر رکھا گیا ہے کہ اس میں جہنم کے
سات دروازوں کی طرف اشارہ ہے.اور ان میں سے ہر ایک دروازہ کے لئے اس سورۃ کا
ایک حصہ مقرر ہے جو خدائے رحمان کے اذن سے جہنم کے شعلوں کو دُور کرتا ہے.پس
جو شخص جہنم کے ان سات دروازوں سے محفوظ گزرنا چاہتا ہے اسے لازم ہے کہ وہ اس سورۃ کی
ساتوں آیات کے حصار میں داخل ہو اور ان سے دلی لگاؤ ر کھے اور ان پر عمل کرنے کے لئے
خدائے قدیر سے استقلال طلب کرے.اور تمام اخلاق، اعمال اور عقائد جو انسان کو جہنم میں
داخل کرتے ہیں وہ اصولی طور پر سات مہلک امور ہیں اور سورت فاتحہ کی یہ سات آیات ایسی
ہیں جو ان مہلکات کی شدائد کو دفع کرتی ہیں.احادیث میں اس سورۃ کے اور بھی کئی نام مذکور ہیں لیکن تیرے لئے اسی قدر بیان کافی ہے
31
Page 40
کہ یہ الہی اسرار کا خزانہ ہے.علاوہ ازیں اس سورت کی آیات کا سات کی تعداد میں منحصر ہونا مبدء و معاد کے زمانہ
کی طرف اشارہ ہے.میری مراد یہ ہے کہ اس کی سات آیات دنیا کی عمر کی طرف اشارہ کرتی
ہیں کہ وہ سات ہزار سال ہے اور ہر آیت ہزار سال کی کیفیت پر دلالت کرتی ہے اور یہ کہ
آخری ہزار سال گمراہی میں بڑھ کر ہوگا اور یہ مقام اسی طرح اظہار کا مقتضی تھا جس طرح یہ سورۃ
شروع دنیا سے لے کر آخرت تک کے ذکر کی کفیل ہے.اعجاز امسیح.روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 74-79)
سورۃ فاتحہ اور قرآن شریف میں ایک اور خاصہ بزرگ پایا جاتا ہے کہ جو اسی کلام
پاک سے خاص ہے اور وہ یہ ہے کہ اس کو تو جہ اور اخلاص سے پڑھنا دل کو صاف کرتا ہے اور
ظلمانی پردوں کو اٹھاتا ہے اور سینے کو منشرح کرتا ہے اور طالب حق کو حضرت احدیت کی
طرف کھینچ کر ایسے انوار اور آثار کا مورد کرتا ہے کہ جو مقر بان حضرت احدیت میں ہونی چاہئے
اور جن کو انسان کسی دوسرے حیلہ یا تدبیر سے ہر گز حاصل نہیں کرسکتا.برا بین احمد یہ چہار حصص ، روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 402.حاشیہ نمبر 11 )
فاتحہ فتح کرنے کو بھی کہتے ہیں.مومن کو مومن اور کافر کو کافر بنادیتی ہے یعنی دونوں
میں ایک امتیاز پیدا کر دیتی ہے اور دل کو کھولتی، سینہ میں ایک انشراح پیدا کرتی ہے.اس
لئے سورہ فاتحہ کو بہت پڑھنا چاہئے اور اس دُعا پر خوب غور کرنا ضروری ہے.ا حکم 24 دسمبر 1900 ، صفحہ 1 -2)
سورۃ فاتحہ تو ایک معجزہ ہے اس میں امر بھی ہے، نہی بھی ہے، پیشگوئیاں بھی ہیں.قرآن
شریف تو ایک بہت بڑا سمندر ہے.کوئی بات اگر نکالنی ہو تو چاہئے کہ سورۃ فاتحہ میں بہت غور
کرے کیونکہ یہ اُٹھ الکتاب ہے.اس کے بطن سے قرآن کریم کے مضامین نکلتے ہیں.(احکم 10 رفروری 1901 صفحہ 12)
سورۃ فاتحہ میں جو پنج وقت ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے اشارہ کے طور پر کل عقائد کا ذکر
32
Page 41
ہے جیسے فرمایا الحَمدُ لِلهِ رَبِّ الْعَلَمِینَ یعنی ساری خوبیاں اس خدا کے لئے سزا وار ہیں جو
سارے جہانوں کو پیدا کرنے والا ہے.آل محمن وہ بغیر اعمال کے پیدا کرنے والا ہے اور بغیر کسی
عمل کے عنایت کرنے والا ہے.الرّحِیم اعمال کا پھل دینے والا ملِكِ يَوْمِ الدِّين جزا سزا
کے دن کا مالک.ان چار صفتوں میں کل دنیا کے فرقوں کا بیان کیا گیا ہے.بعض لوگ اس بات سے منکر ہیں کہ خدا ہی تمام جہانوں
کا پیدا کرنے والا ہے.وہ کہتے ہیں کہ
جیو یعنی ارواح اور پر مانویعنی ذرات خود بخود ہیں اور جیسے پر میشر آپ ہی آپ چلا آتا ہے ویسے ہی
وہ بھی آپ ہی آپ چلے آتے ہیں اور ارواح اور ان کی کل طاقتیں، گن اور خواص جن پر دفتروں کے
دفتر لکھے گئے خود بخود ہیں اور باوجود اس کے کہ ان میں قوت اتصال اور قوت انفصال خود بخود پائی جاتی
ہے وہ آپس میں میل ملاپ کرنے کے لئے ایک پرمیشر کے محتاج ہیں.غرض یہ وہ فرقہ ہے جس
کی طرف اللہ تعالیٰ نے رَبُّ الْعَلَمِینَ کہہ کر اشارہ کیا ہے.دوسرا فرقہ وہ ہے جس کی طرف الرحمن کے لفظ میں اشارہ ہے اور یہ فرقہ سناتن دھرم
والوں کا ہے گو وہ مانتے ہیں کہ پرمیشر سے ہی سب کچھ نکلا ہے مگر وہ کہتے ہیں کہ خدا کا فضل
کوئی چیز نہیں وہ کرموں کا ہی پھل دیتا ہے.یہاں تک کہ اگر کوئی مرد بنا ہے تو وہ بھی اپنے
اعمال سے اور اگر کوئی عورت بنی ہے تو وہ بھی اپنے اعمال سے اور اگر ضروری اشیاء حیوانات
نباتات وغیرہ بنے ہیں تو وہ بھی اپنے اپنے کرموں کی وجہ سے.الغرض یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی
صفت رحمن سے منکر ہیں.وہ خدا جس نے زمین ، سورج ، چاند ستارے وغیرہ پیدا کئے اور ہوا
پیدا کی تا کہ ہم سانس لے سکیں اور ایک دوسرے کی آواز سن سکیں اور روشنی کے لیے سورج چاند
وغیرہ اشیاء پیدا کیں اور اس وقت پیدا کیں جب کہ ابھی سانس لینے والوں کا وجود اور نام ونشان
بھی نہ تھا.تو کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ سب کچھ ہمارے ہی اعمال کی وجہ سے پیدا کیا گیا
ہے؟ کیا کوئی اپنے اعمال کا دم مار سکتا ہے؟ کیا کوئی دعوی کر سکتا ہے کہ یہ سورج چاند
ستارے ہوا وغیرہ میرے اپنے عملوں کا پھل ہے؟ غرض خدا کی صفت رحمانیت اس فرقہ کی
تردید کرتی ہے جو خدا کو بلا مبادلہ یعنی بغیر ہماری کسی محنت اور کوشش کے بعض اشیاء کے
33
Page 42
عنایت کرنے والا نہیں مانتے.اس کے بعد خدا تعالیٰ کی صفت الرحیم کا بیان ہے یعنی محنتوں کوششوں اور اعمال پر
شمراتِ حسنہ مرتب کرنے والا.یہ صفت اس فرقہ کو رڈ کرتی ہے جو اعمال کو بالکل لغو خیال
کرتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ میاں نما ز کیا تو روزے کیا ؟ اگر غَفُورُ الرَّحِیم نے
اپنا فضل کیا تو بہشت میں جائیں گے.نہیں تو جہنم میں.اور کبھی کبھی یہ لوگ اس قسم کی باتیں
بھی کہہ دیا کرتے ہیں کہ میاں عبادتاں کر کے ولی تو ہم نے کچھ تھوڑا ہی بننا ہے.کچھ کیتا
کھیتا، نہ کیتا نہ ہیں.الغرض الرحِیم کہ کر خدا ایسے ہی لوگوں کا رد کرتا ہے اور بتایا ہے کہ جو
محنت کرتا ہے اور خدا کے عشق اور محبت میں محو ہو جاتا ہے وہ دوسروں سے ممتا ز اور خدا کا منظور
نظر ہوجاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی خود دستگیری کرتا ہے جیسے فرمایا.وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوا
فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا (العنكبوت (70 یعنی جو لوگ ہماری خاطر مجاہدات کرتے
ہیں آخر ہم ان کو اپنا راستہ دکھا دیتے ہیں.جتنے اولیاء اور انبیاء اور بزرگ لوگ گزرے ہیں
انہوں نے خدا کی راہ میں جب بڑے بڑے مجاہدات کئے تو آخر خدا نے اپنے دروازے ان
پر کھول دیے.لیکن وہ لوگ جو خدا تعالیٰ کی اس صفت کو نہیں مانتے.عموماً ان کا یہی مقولہ
ہوتا ہے کہ میاں ہماری کوششوں میں کیا پڑا ہے جو کچھ تقدیر میں پہلے روز سے لکھا ہے وہ
تو ہو کر رہے گا.ہماری محنتوں کی کوئی ضرورت نہیں جو ہونا ہے وہ آپ ہی ہو جائے گا.اور
شاید چوروں اور ڈاکوؤں اور دیگر بد معاشوں کا اندر ہی اندر یہی مذہب ہوتا ہوگا.( الحکم 2 رجنوری 1908 صفحہ 6)
سورۃ فاتحہ کی سات آیتیں اسی واسطے رکھی ہیں کہ دوزخ کے سات دروازے ہیں.پس
ہر ایک آیت گویا ایک دروازہ سے بچاتی ہے.حق بات یہی ہے کہ سورت فاتحہ ہر علم اور معرفت پر محیط ہے وہ سچائی اور حکمت کے تمام
نکات پر مشتمل ہے اور یہ ہر سائل کے سوال کا جواب دیتی اور ہر حملہ آور دشمن کو تباہ کرتی ہے.نیز ہر مسافر کو جو مہمان نوازی چاہتا ہے کھلاتی اور آنے اور جانے والوں کو پلاتی ہے.34
Page 43
بے شک وہ ہر شبہ کو جو نا کامی کی حد تک پہنچانے والا ہو زائل کر دیتی ہے اور ہر غم کو جس نے
بوڑھا کر دیا ہو جڑ سے اکھیڑ دیتی ہے اور ہر گمشدہ راہنما کو ( راہ راست پر ) واپس لاتی ہے اور ہر
خطرناک دشمن کو شرمندہ کرتی ہے.طالبانِ ہدایت کو بشارت دیتی ہے.گناہوں کے زہر اور دلوں
کی کجی کے لیے اس جیسا کوئی اور معالج نہیں اور وہ حق اور یقین تک پہنچانے والی ہے.کرامات الصادقین.روحانی خزائن جلد 7 صفحہ 145)
ایک خاصہ روحانی سورہ فاتحہ میں یہ ہے کہ دلی حضور سے اپنی نماز میں اس کو ورد کر لینا
اور اس کی تعلیم کو فی الحقیقت سچ سمجھ کر اپنے دل میں قائم کر لینا تنویر باطن میں نہایت دخل رکھتا
ہے.یعنی اس سے انشراح خاطر ہوتا ہے اور بشریت کی ظلمت دور ہوتی ہے اور حضرت
مبدء فیوض کے فیوض انسان پر وارد ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور قبولیتِ الہی کے انوار اس پر
احاطہ کر لیتے ہیں.یہاں تک کہ وہ ترقی کرتا کرتا مخاطبات الہیہ سے سرفراز ہو جاتا ہے اور
کشوف صادقہ اور الہامات واضحہ سے تمتع تام حاصل کرتا ہے اور حضرت الوہیت کے مقربین
میں دخل پالیتا ہے اور وہ وہ عجائبات القائے غیبی اور کلام لا ریبی اور استجابت ادعیہ اور کشف
مغیبات اور تائید حضرت قاضی الحاجات اُس سے ظہور میں آتی ہیں کہ جس کی نظیر اس کے غیر میں
نہیں پائی جاتی.(براہین احمدیہ چہار حصص - روحانی خزائن جلد اول حاشیہ نمبر 11 صفحہ 626-629)
یہ عاجز اپنے ذاتی تجربہ سے بیان کرتا ہے کہ فی الحقیقت سورہ فاتحہ مظہر انوار الہی
ہے.اس قدر عجائبات اس سورۃ کے پڑھنے کے وقت دیکھے گئے ہیں کہ جن سے خدا کے پاک
کلام کا قدر و منزلت معلوم ہوتا ہے.اس سورہ مبارکہ کی برکت سے اور اس کے تلاوت کے
التزام سے کشف مغیبات اس درجہ تک پہنچ گیا کہ صد با اخبار غیبیہ قبل از وقوع منکشف ہوئیں
اور ہر یک مشکل کے وقت اس کے پڑھنے کی حالت میں عجیب طور پر رفع حجاب کیا گیا اور
قریب تین ہزار کے کشف صحیح اور رویا صادقہ یاد ہے کہ جواب تک اس عاجز سے ظہور میں
آچکے اور صبح صادق کے کھلنے کی طرح پوری بھی ہو چکی ہیں.اور دوسو جگہ سے زیادہ قبولیت دعا
35
Page 44
کے آثار نمایاں ایسے نازک موقعوں پر دیکھے گئے جن میں بظاہر کوئی صورت مشکل کشائی کی نظر
نہیں آتی تھی اور اسی طرح کشف قبور اور دوسرے انواع اقسام کے عجائبات اسی سورۃ کے
التزام ورد سے ایسے ظہور پکڑتے گئے کہ اگر ایک ادنی پر توہ اُن کا کسی پادری یا پنڈت کے دل
پر پڑ جائے تو ایک دفعہ حُبّ دنیا سے قطع تعلق کر کے اسلام کے قبول کرنے کے لئے مرنے
پر آمادہ ہو جائے.اسی طرح بذریعہ الہامات صادقہ کے جو پیشگوئیاں اس عاجز پر ظاہر ہوتی
رہی ہیں جن میں سے بعض پیشگوئیاں مخالفوں کے سامنے پوری ہوگئی ہیں اور پوری ہوتی جاتی
ہیں اس قدر ہیں کہ اس عاجز کے خیال میں دو انجیلوں کی ضخامت سے کم نہیں اور یہ عاجز بطفیل
متابعت حضرت رسول کریم مخاطبات حضرت احدیت میں اس قدر عنایات پاتا ہے کہ جس کا
کچھ تھوڑا سا نمونہ حاشیہ در حاشیہ نمبر 3 کے عربی الہامات وغیرہ میں لکھا گیا ہے.خداوند کریم
نے اسی رسول مقبول کی متابعت اور محبت کی برکت سے اور اپنے پاک کلام کی پیروی کی تاثیر
سے اس خاکسار کو اپنے مخاطبات سے خاص کیا ہے اور علوم لد حمیہ سے سرفراز فرمایا ہے اور
بہت سے اسرار مخفیہ سے اطلاع بخشی ہے اور بہت سے حقائق اور معارف سے اس ناچیز کے
سینہ کو پُر کر دیا ہے اور بار ہا بتلا دیا ہے کہ یہ سب عطیات اور عنایات اور یہ سب تفضلات اور
احسانات اور یہ سب تلطفات اور توجہات اور یہ سب انعامات اور تائیدات اور یہ سب
مکالمات اور مخاطبات یمن متابعت و محبت حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہیں.برائین احمدیہ چہار حصص - روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 642-646 حاشیہ نمبر (11)
سورۃ فاتحہ ایک محفوظ قلعہ، نُورمبین اور استاد و مددگار ہے اور یہ احکام قرآنیہ کو بڑے
اہتمام سے کمی بیشی سے محفوظ رکھتی ہے جس طرح سرحدوں کی حفاظت کی جاتی ہے اور اس کی
مثال اس اونٹنی کی ہے جس کی پیٹھ پر تیری ضرورت کی ہر چیز لدی ہوئی ہو اور وہ اپنے سوار کو
دیار محبوب تک پہنچا دے.نیز اس پر ہر قسم کا زادراہ، نفقہ اور لباس و پوشاک لدی ہوئی ہو.یا
پھر اس کی مثال اس چھوٹے سے حوض کی ہے جس میں بہت سا پانی ہو گویا کہ وہ متعدد دریاؤں
کا منبع ہے، یاوہ ایک عظیم دریا کی گذرگاہ ہے.اور میں دیکھتا ہوں کہ اس سورۃ کریمہ کے فوائد
36
Page 45
اور خوبیاں ان گنت ہیں اور ان کا شمار انسانی طاقت میں نہیں خواہ کوئی اس خواہش کی تکمیل میں
اپنی عمر گزار دے.گمراہ اور بد بخت لوگوں نے اپنی جہالت اور کند ذہنی کی بناء پر اس کی صحیح قدر
نہیں کی.انہوں نے اسے پڑھا تو سہی لیکن باوجود بار بار پڑھنے کے وہ اس کی خوبی اور خوبصورتی
کو نہ پاسکے.یہ سورت منکروں پر شدت سے حملہ کرنے والی اور صحت مند دلوں پر شرعت سے
اثر کرنے والی ہے.ہر وہ شخص جس نے اس پر ایک پر کھنے والے کی طرح نظر ڈالی اور چمکتے
ہوئے چراغ کی مانند روشن فکر کے ساتھ اس کے قریب ہوا اس نے اس کو آنکھوں کا نور اور
اسرار کی کلید پایا.بلاشک وشبہ یہی بات حق ہے اور نہ یہ کوئی ظنی بات ہے.اگر تمہیں کوئی
شک ہو تو اٹھو اور خود اس کا تجربہ کرلو اور ماندگی دستی کو چھوڑ دو اور یہ سوال نہ کرو کہ یہ
کیسے اور کہاں ہو سکتا ہے.اس سورت کے عجائبات میں سے یہ بات بھی ہے کہ اس نے
اللہ تعالیٰ کی تعریف ایسے الفاظ میں بیان کی ہے کہ اس سے زیادہ بیان کرنا انسان کی
طاقت میں نہیں.ہم دُعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان اس
سورۃ فاتحہ کے ذریعہ فیصلہ کر دے.ہمارا اُسی پر توکل ہے.آمین یا رب العالمین.اعجاز امسیح.روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 79-81)
سورۃ فاتحہ کا نماز میں پڑھنا لازمی ہے اور یہ دعا ہی ہے جس سے صاف معلوم ہوتا ہے
کہ اصل دُعا نماز ہی میں ہوتی ہے.چنانچہ اس دُعا کو اللہ تعالیٰ نے یوں سکھایا ہے.الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم...إلى أخر لا یعنی دعاسے پہلے یہ ضروری
ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمدوثنا کی جاوے.جس سے اللہ تعالیٰ کے لئے روح میں ایک جوش اور محبت
پیدا ہو.اس لئے فرمایا الحمد للہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں.رَبِّ الْعَالَمِينَ
سب کو پیدا کرنے والا اور پالنے والا.الرحمن جو بلا عمل اور بن مانگے دینے والا ہے.الرَّحِيمِ پھر عمل پر بھی بدلہ دیتا ہے.اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دیتا ہے.ملِكِ يَوْمِ
الدین ہر بدلہ اسی کے ہاتھ میں ہے.نیکی بدی سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے.پورا اور
کامل موحد تب ہی ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کو ملِكِ يَوْمِ اللي بين تسلیم کرتا ہے.دیکھو گام
37
Page 46
کے سامنے جا کر ان کو سب کچھ تسلیم کر لینا یہ گناہ ہے اور اس سے شرک لازم آتا ہے.اس لحاظ
سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حاکم بنایا ہے.ان کی اطاعت ضروری ہے مگر ان کو خدا ہر گز نہ بناؤ.انسان کا حق انسان کو اور خدا تعالیٰ کا حق خدا تعالیٰ کو دو.پھر یہ کہو.إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ
نَسْتَعِينُ.ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں.اھدِنَا
الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيم..الخ ہم کو سیدھی راہ دکھا.یعنی ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کئے
اور وہ نبیوں ،صدیقوں ،شہیدوں اور صالحین کا گروہ ہے.اس دُعا میں ان تمام گروہوں کے فضل
اور انعام کو مانگا گیا ہے.ان لوگوں کی راہ سے بچا جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے.الحکم نمبر 23 جلد 6 مؤرخہ 24 جون 1902 ، صفحہ 2)
اس سورہ میں تین لحاظ رکھنے چاہئیں (1) ایک یہ کہ تمام بنی نوع کو اس میں شریک
رکھے(2) تمام مسلمانوں کو (3) تیسرے ان حاضرین کو جو جماعت نماز میں داخل ہیں.پس
اس طرح کی نیت سے کل نوع انسان اس میں داخل ہوں گے اور یہی منشاء خدا تعالیٰ کا ہے.مکتوب حضرت مسیح موعود بنام شیخ غلام نبی صاحب مندرجہ الکم نمبر 20، 21 جلد 40 مؤرخہ 28 جولائی.7 اگست 1937ء
صفحہ 3)
نماز میں سورۃ فاتحہ کی دعا کا تکرار نہایت موثر چیز ہے.کیسی ہی بے ذوقی و بے مزگی ہو اس
عمل کو برابر جاری رکھنا چاہئے.یعنی کبھی تکرار آیت إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کا اور
کبھی تکرار آیت اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کا اور سجدہ میں يَاحَنُ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ
اسْتَغِيْتُ
الحکم نمبر 1 جلد 2 مؤرخہ 20 فروری1898 صفحہ 9)
حملا سورۃ فاتحہ کا ورد نماز میں بہتر ہے.بہتر ہے کہ نماز تہجد میں اهْدِنَا الصِّراط
الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمُ کا بدلی توجہ وخضوع و خشوع تکرار
کریں اور اپنے دل کو نزول انوار الہیہ کے لئے پیش کریں اور کبھی تکرار آیت انیاک
نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کا کیا کریں.ان دونوں آیتوں کا تکرار انشاء اللہ القدیر تنویر
38
Page 47
قلب و تزکیہ نفس کا موجب ہوگا.احکم نمبر 23 جلد 7 مؤرخہ 24 / جون 1903، صفحہ 3)
قرآن شریف میں چار سورتیں ہیں جو بہت پڑھی جاتی ہیں.اُن میں مسیح موعود اور اس
کی جماعت کا ذکر ہے.(1) سورۃ فاتحہ جو ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے اس میں ہمارے
دعوے کا ثبوت ہے.جیسا کہ اس تفسیر میں ثابت کیا جائے گا.(2 ) سورہ جمعہ جس میں اخرین
منهم مسیح موعود کی جماعت کے متعلق ہے یہ ہر جمعہ میں پڑھی جاتی ہے.(3) سورہ کہف
جس کے پڑھنے کے واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے.اس کی پہلی اور
پچھلی دس آیتوں میں دجال کا ذکر ہے.(4) آخری سورت قرآن کی جس میں دجال کا نام
خناس رکھا گیا ہے.یہ وہی لفظ ہے جو عبرانی توریت میں دجال کے واسطے آیا ہے.یعنی
محاش wna.ایسا ہی قرآن شریف کے اور مقامات میں بھی بہت ذکر ہے.الحکم جلد 5 نمبر 3 مورخہ 24 جنوری 1901ء صفحہ 11)
جب کوئی شخص سورۃ فاتحہ اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگے تو اس پر لازم ہے کہ وہ
أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ پڑھے جیسا کہ قرآن کریم میں حکم ہے.کیونکہ کبھی
شیطان خدا تعالیٰ کی رکھ میں چوروں کی طرح داخل ہو جاتا ہے اور اس حرم کے اندر آ جاتا ہے جو
معصومین کا محافظ ہے.پس اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ وہ سورۃ فاتحہ اور قرآن مجید کی تلاوت
کے وقت اپنے بندوں کو شیطان کے حملہ سے بچائے ، اُسے اپنے حربہ سے پسپا کرے، اس کے
سر پر تبر رکھے اور غافلوں کو غفلت سے نجات دے.پس اس نے شیطان کو دھتکارنے کے
لئے جو قیامت تک راندہ درگاہ ہے اپنے ہاں سے بندوں کو ایک بات سکھائی اور اس مخفی امریعنی
تعوذ میں یہ راز ہے کہ شیطان قدیم سے انسان کا دشمن ہے اور وہ اسے پوشیدہ اور اچانک طور پر
بلاک اور برباد کرنا چاہتا ہے.اس کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ چیز انسان کو تباہ کرنا
ہی ہے اس لئے اس نے اپنے نفس پر یہ لازم کر لیا ہے کہ وہ ہر اس امر کی طرف کان لگائے
رکھے جو خدائے رحمان کی طرف سے لوگوں کو جنت کی طرف بلانے کے لئے نازل ہوتا ہے
39
Page 48
اور وہ اپنی تمام تر کوشش گمراہی اور فتنہ کے پھیلانے میں خرچ کرے.پس اللہ تعالیٰ نے انبیاء
کی بعثت کے ذریعہ اس کے لئے ناکامی اور تلخیاں مقدر کر رکھی ہیں.اللہ تعالیٰ نے اُسے
( شروع میں ) قتل تو نہیں کیا بلکہ اُسے اس وقت تک مہلت دے دی جب مُردے خدا تعالیٰ
بزرگ و برتر کی اجازت سے دوبارہ زندہ کئے جائیں گے اور اس نے تعوذ میں الشَّيْطَانِ
الرَّجِيْمِ کے الفاظ رکھ کر اس کے قتل کی خبر دی ہے.پس یہی وہ کلمہ ہے جو بشیر اللہ
الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ سے قبل پڑھا جاتا ہے.اور یہ رجیم وہی ہے جس کے حق میں ایک خاص وعید آئی ہے.اس سے میری مراد وہ دنبال
ہے جسے مسیح موعود ( قاتل دجال ) بلاک کرے گا اور رجیم کے معنے قتل کے ہیں.جیسا کہ عربی
زبان کی کتب لغت میں اس کی تصریح کی گئی ہے.پس رجیم وہی دجل کرنے والا ہے جو آئندہ
زمانہ میں بلاک کیا جائے گا.یہ اس خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے جو اپنے بندوں کا لحاظ رکھتا ہے.اور
اللہ تعالیٰ کے الفاظ اٹل ہوتے ہیں.پس خدائے رحیم کی طرف سے مسلمانوں کے لئے
بشارت ہے اور اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایک وقت دجال کو بلاک کیا جائے گا جیسا کہ
لفظ رجیم سے واضح ہے.(1) اس مقام میں رجم کے معنے جیسا کہ مجھے مخلوق کے رب کی طرف سے علم دیا گیا ہے.(2) وہ کمینوں کو عاجز کرنا اور ایسے دشمنوں کو لاجواب کرنا ہے جو اندھیرے کی پناہ گاہ ہیں.(3) اور ایسی ضرب لگانا ہے جو خصومت کو جڑ سے اکھیڑ دے ہماری مراد اس سے تلوار کی
ضرب نہیں.اب وہ زمانہ آ گیا ہے جس میں باطل ہلاک ہو جائے گا اور جھوٹ اور اندھیرا باقی نہیں
رہے گا.تمام مذاہب سوائے اسلام کے مٹ جائیں گے اور زمین انصاف، عدل اور نور سے
بھر جائے گی جیسا کہ وہ پہلے ظلم ، کفر ، تعدی اور جھوٹ سے پڑ تھی.پس اس وقت اس گروہ دنبال
کوجس کی ہلاکت کا وعدہ پہلے سے دیا گیا ہے قتل کیا جائے گا.اس جگہ قتل سے ہماری مراد
صرف اس کی طاقت توڑ دینے اور اس کے قیدیوں کو آزاد کر دینے سے ہے.40
Page 49
پس خلاصہ کلام یہ ہے کہ جسے شیطان رجیم کہتے ہیں اس سے وہی دجال لتیم ، خناس قدیم مراد
ہے جس کا قتل کیا جانا ایک موعود امر تھا اور ایسا اہم امر تھا جو پہلے ہی مقدر ہو چکا تھا.اسی لئے اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں پر واجب قرار دیا کہ وہ سورۃ فاتحہ اور بسم اللہ
الرّحمٰنِ الرَّحِیمِ پڑھنے سے قبل اَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ پڑھیں تا کہ
پڑھنے والے کے ذہن نشین رہے کہ دجال کا زمانہ اس قوم کے زمانہ سے تجاوز نہیں کرے گا
جس کا ذکر ان سات آیتوں میں سے آخری آیت میں کیا گیا ہے اور اللہ کی یہ تقدیر ابتدائے
زمانہ سے مقرر تھی کہ مذکور شیطان رجیم آخری زمانہ میں قتل ہوگا اور لوگ اس زہریلے اثر دبا کے
ڈسنے سے امان پا جائیں گے.پس اب زمانہ اپنے انتہائی دور میں پہنچ گیا ہے اور دنیا کی عمر سبع
مثانی کی سات آیات کی طرح شمسی اور قمری حساب سے ساتویں ہزار سال میں پہنچ گئی ہے.آج یہ شیطان رجیم ایسے گروہ کی صورت میں ظاہر ہوا ہے جو اس کے لئے بروزی لباس کی
حیثیت رکھتا ہے اور گمراہی اس قوم پر ختم ہوگئی ہے جس کا ذکر سورۃ فاتحہ کے آخری الفاظ میں آیا
ہے اور اس بات کو وہی سمجھ سکتا ہے جو روشن طبع ہو.اور یہ دنبال صرف آسمانی حربہ سے ہی بلاک کیا جائے گا.یعنی بشری طاقت سے نہیں بلکہ
خدا تعالیٰ کے فضل سے ہی قتل ہوگا.پس نہ کوئی لڑائی ہوگی نہ مار پیٹ.بلکہ یہ ایک ایسا امر
ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے وقوع پذیر ہوگا اور یہ دجال ( شیطان ) ہر صدی میں اپنی ذریت
میں سے بعض کو مقرر کرتا رہا تا مومنوں ، موحدوں، نیکوکاروں ،حق پر قائم لوگوں اور اس کے
طالبوں کو گمراہ کرے اور دین کی عمارتوں کو گرا دے اور اللہ تعالی کی کتب کو پارہ پارہ کر دے.یہ
اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ وہ دجال آخری زمانہ میں قتل کیا جائے گا اور نیکی ہر قسم کی خرابی اور سرکشی
پر غالب آ جائے گی اور زمین بدل دی جائے گی اور اکثر لوگ خدائے رحمان کی طرف رجوع
کرلیں گے.زمین اپنے رب کے نور سے روشن ہو جائے گی اور قلوب شیطانی تاریکیوں سے باہر
آجائیں گے.یہی باطل کی موت ، دنبال کی موت اور اس بڑے اثر دبا کا قتل ہے.41
Page 50
کیا لوگ کہتے ہیں کہ دجال ایک شخص ہے جو سی زمانہ میں قتل کیا جائے گا؟ ایسا ہر گز نہیں.بلکہ دجال تو وہ مردود شیطان ہے جو بدیوں کا سر چشمہ ہے.اُسے آخری زمانہ میں جہالتوں کے
دور کرنے اور بدیوں کو مٹانے کے ذریعہ قتل کیا جائے گا.یہ خدائے رحیم کا سچا وعدہ ہے جیسا کہ
خدا کے الفاظ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے.پس ہمارے پروردگار کی
پیشگوئی راستی و عدل سے اس زمانہ میں پوری ہو گئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کی طرف نظر کرم فرمائی
بعد اس کے کہ اس پر مصائب و تکالیف وارد ہوئیں.پس اللہ تعالیٰ نے اپنے مسیح کو اس خناس
شیطان کے قتل اور اس جھگڑے کے چکانے کیلئے نازل کیا.اور شیطان کا نام رجیم بطور پیشگوئی رکھا گیا ہے کیونکہ رجم کے معنے بلا شک و شبہ قتل کرنے
کے ہیں اور جب مقدر یوں تھا کہ یہ دجال خدائے ذوالجلال کے مسیح کے نازل ہونے کے
زمانہ میں قتل کیا جائے گا.لہذا اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ سے قبل ہی ان لوگوں کی تسلی اور
بشارت کے لئے جو گمراہی کے زمانہ سے ڈرتے ہیں خبر دے دی.بسم الله الرحمنِ الرَّحِيمِ
اعجاز امسیح.روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 81-89)
یہ آیت سورۃ ممدوحہ ( یعنی سورۃ فاتحہ ) کی آیتوں میں سے پہلی آیت ہے اور قرآن
شریف کی دوسری سورتوں پر بھی لکھی گئی ہے اور ایک اور جگہ بھی قرآن شریف میں یہ آیت آئی
ہے اور جس قدر تکرار اس آیت کا قرآن شریف میں بکثرت پایا جاتا ہے اور کسی آیت میں اس
قدر تکرار نہیں پایا جاتا.اور چونکہ اسلام میں یہ سنت ٹھہر گئی ہے کہ ہر ایک کام کے ابتدا میں جس
میں خیر اور برکت مطلوب ہو بطریق تبرک اور استمداد اس آیت کو پڑھ لیتے ہیں اس لئے یہ
آیت دشمنوں اور دوستوں اور چھوٹوں اور بڑوں میں شہرت پاگئی ہے یہاں تک کہ اگر کوئی شخص
تمام قرآنی آیات سے بے خبر مطلق ہو.تب بھی امید قوی ہے کہ اس آیت سے ہر گز اس کو
بے خبری نہیں ہوگی.42
Page 51
اب یہ آیت جن کامل صداقتوں پر مشتمل ہے ان کو بھی سن لینا چاہئے.سو منجملہ ان کے
ایک یہ ہے کہ اصل مطلب اس آیت کے نزول سے یہ ہے کہ تا عاجز اور بے خبر بندوں کو اس
نکتہ معرفت کی تعلیم کی جائے کہ ذات واجب الوجود کا اسم اعظم جو اللہ ہے کہ جو اصطلاح قرآنی
ربانی کے رُو سے ذات مستجمع جمیع صفات کا ملہ اور منزه عن جميع رذائل اور معبود برحق اور واحد لا
شریک اور مبدء جمیع فیوض پر بولا جاتا ہے.اس اسم اعظم کی بہت سی صفات میں سے جو دو
صفتیں بسم اللہ میں بیان کی گئی ہیں یعنی صفت رحمانیت و رحیمیت انہیں دو صفتوں کے تقاضا
سے کلام الہی کا نزول اور اس کے انوار و برکات کا صدور ہے.اس کی تفصیل یہ ہے کہ خدا کے
پاک کلام کا دنیا میں اترنا اور بندوں کو اس سے مطلع کیا جانا یہ صفت رحمانیت کا تقاضا ہے کیونکہ
صفت رحمانیت کی کیفیت (جیسا کہ آگے بھی تفصیل سے لکھا جائے گا) یہ ہے کہ وہ صفت بغیر
سبقت عمل کسی عامل کے محض مجود اور بخشش الہی کے جوش سے ظہور میں آتی ہے جیسا خدا نے
سورج اور چاند اور پانی اور ہوا وغیرہ کو بندوں کی بھلائی کے لئے پیدا کیا ہے.یہ تمام جود اور
بخشش صفت رحمانیت کے رو سے ہے.اور کوئی شخص دعوی نہیں کرسکتا کہ یہ چیزیں میرے
کس عمل کی پاداش میں بنائی گئی ہیں.اسی طرح خدا کا کلام بھی کہ جو بندوں کی اصلاح اور
رہنمائی کے لئے اتر اوہ بھی اس صفت کے رُو سے اترا ہے.اور کوئی ایسا متنفس نہیں کہ یہ دعویٰ
کر سکے کہ میرے کسی عمل یا مجاہدہ یا کسی پاک باطنی کے اجر میں خدا کا پاک کلام کہ جو اس کی
شریعت پر مشتمل ہے نازل ہوا ہے.یہی وجہ ہے کہ اگر چہ طہارت اور پاک باطنی کا دم
مارنے والے اور زہد اور عبادت میں زندگی بسر کرنے والے اب تک ہزاروں لوگ گزرے
ہیں لیکن خدا کا پاک اور کامل کلام کہ جو اُس کے فرائض اور احکام کو دنیا میں لایا اور اس کے
ارادوں سے خلق اللہ کو مطلع کیا اُنہیں خاص وقتوں میں نازل ہوا ہے کہ جب اس کے نازل
ہونے کی ضرورت تھی.ہاں یہ ضرور ہے کہ خدا کا پاک کلام انہیں لوگوں پر نا زل ہو کہ جو تقدس
اور پاک باطنی میں اعلیٰ درجہ رکھتے ہوں.کیونکہ پاک کو پلید سے کچھ میل اور مناسبت نہیں
لیکن یہ ہر گز ضرور نہیں کہ ہر جگہ تقدس اور پاک باطنی کلام الہی کے نازل ہونے کو مستلزم ہو بلکہ
43
Page 52
خدائے تعالی کی حقانی شریعت اور تعلیم کا نازل ہونا ضرورات حقہ سے وابستہ ہے.پس جس
جگہ ضرورات حقہ پیدا ہوگئیں اور زمانہ کی اصلاح کے لئے واجب معلوم ہوا کہ کلام الہی نازل ہو
اسی زمانہ میں خدائے تعالیٰ نے جو حکیم مطلق ہے اپنے کلام کو نازل کیا اور کسی دوسرے زمانہ
میں گولاکھوں آدمی تقویٰ اور طہارت کی صفت سے متصف ہوں اور گو کیسی ہی تقدس اور پاک
باطنی رکھتے ہوں ان پر خدا کا وہ کامل کلام ہر گز نا زل نہیں ہوتا کہ جو شریعت حقانی پر مشتمل ہو.ہاں مکالمات و مخاطبات حضرت احدیت کے بعض پاک باطنوں سے ہو جاتے ہیں اور وہ بھی
اس وقت کہ جب حکمت الہیہ کے نزدیک ان مکالمات اور مخاطبات کے لئے کوئی
ضرورت حقہ پیدا ہو.کسی فرد انسانی کا کلام الہی کے فیض سے فی الحقیقت مستفیض ہو جانا اور اس کی برکات اور
انوار سے متمتع ہو کر منزل مقصود تک پہنچنا اور اپنی سعی اور کوشش کے ثمرہ کو حاصل کرنا یہ صفتِ
رحیمیت کی تائید سے وقوع میں آتا ہے.اور اسی جہت سے خدائے تعالیٰ نے بعد ذکر صفتِ
رحمانیت کے صفت رحیمیت کو بیان فرمایا تا معلوم ہو کہ کلام الہی کی تاثیر میں جو نفوس انسانیہ
میں ہوتی ہیں یہ صفت رحیمیت کا اثر ہے.جس قدر کوئی اعراض صوری و معنوی سے پاک
ہوجاتا ہے.جس قدر کسی کے دل میں خلوص اور صدق پیدا ہوتا ہے جس قدر کوئی جدو جہد سے
متابعت اختیار کرتا ہے.اسی قدر کلام الہی کی تاثیر اس کے دل پر ہوتی ہے اور اسی قدر وہ اس
کے انوار سے متمتع ہوتا ہے اور علامات خاصہ مقبولانِ الہی کی اس میں پیدا ہو جاتی ہیں.یہ آیت قرآن شریف کے شروع کرنے کے لئے نازل ہوئی ہے اور اس کے پڑھنے
سے مدعا یہ ہے کہ تا اس ذات مستجمع جمیع صفات کا ملہ سے مدد طلب کی جائے جس کی صفتوں میں
سے ایک یہ ہے کہ وہ رحمان ہے اور طالب حق کے لئے محض تفضل اور احسان سے اسباب خیر
اور برکت اور رشد کے پیدا کر دیتا ہے اور دوسری صفت یہ ہے کہ وہ رحیم ہے یعنی سعی اور
کوشش کرنے والوں کی کوششوں کو ضائع نہیں کرتا بلکہ ان کے جدو جہد پر شمراتِ حسنہ
مترتب کرتا ہے اور ان کی محنت کا پھل ان کو عطا فرماتا ہے اور یہ دونوں صفتیں یعنی رحمانیت اور
44
Page 53
رحیمیت ایسی ہیں کہ بغیر ان کے کوئی کام دنیا کا ہو یا دین کا انجام کو پہنچ نہیں سکتا اور اگر غور
کر کے دیکھو تو ظاہر ہو گا کہ دنیا کی تمام مہمات کے انجام دینے کے لئے یہ دونوں صفتیں ہر وقت
اور ہر لحظہ کام میں لگی ہوئی ہیں.آیت ممدوحہ کی تعلیم سے مطلب یہ ہے کہ قرآن شریف کے شروع کرنے کے وقت
اللہ تعالیٰ کی ذات جامع صفات کاملہ کی رحمانیت اور رحیمیت سے استمداد اور برکت طلب کی
جائے.صفت رحمانیت سے برکت طلب کرنا اس غرض سے ہے کہ تا وہ ذاتِ کامل اپنی
رحمانیت کی وجہ سے اس سب اسباب کو محض لطف اور احسان سے میسر کر دے کہ جو کلام الہی کی
متابعت میں جدو جہد کرنے سے پہلے درکار ہیں جیسے عمر کا وفا کرنا، فرصت اور فراغت کا حاصل
ہونا، وقت صفا میسر آجانا ، طاقتوں اور قوتوں کا قائم ہونا، کوئی ایسا امر پیش نہ آ جانا کہ جو آسائش
اور امن میں خلل ڈالے، کوئی ایسا مانع نہ آ پڑنا کہ جو دل کو متوجہ ہونے سے روک دے.غرض
ہر طرح سے تو فیق عطا کئے جانا یہ سب امور صفتِ رحمانیت سے حاصل ہوتے ہیں.اور صفتِ
رحیمیت سے برکت طلب کرنا اس غرض سے ہے کہ تا وہ ذات کامل اپنی رحیمیت کی وجہ سے
انسان کی کوششوں پر ثمرات حسنہ مترتب کرے اور انسان کی محنتوں کو ضائع ہونے سے
بچاوے اور اس کی سعی اور جدوجہد کے بعد اس کے کام میں برکت ڈالے.پس اس طور پر
خدائے تعالیٰ کی دونوں صفتوں رحمانیت اور رحیمیت سے کلام الہی کے شروع کرنے کے وقت
بلکہ ہر یک ذیشان کام کے ابتدا میں تبرک اور استمداد چاہنا یہ نہایت اعلیٰ درجہ کی صداقت ہے
جس سے انسان کو حقیقت توحید کی حاصل ہوتی ہے اور اپنے جہل اور بے خبری اور نادانی اور
گمراہی اور عاجزی اور خواری پر یقین کامل ہو کر مبدء فیض کی عظمت اور جلال پر نظر جا ٹھہرتی ہے
اور اپنے تئیں بکلی مفلس اور مسکین اور پیچ اور ناچیز سمجھ کر خداوند قادر مطلق سے اس کی رحمانیت
اور رحیمیت کی برکتیں طلب کرتا ہے.(براہین احمدیہ چہار حصص - روحانی خزائن جلد اوّل صفحہ 414-423 حاشیہ نمبر (11)
اسم کا لفظ ( جو بسم اللہ میں آیا ہے ) وسم سے مشتق ہے اور وشم عربی زبان
45
Page 54
میں داغ دینے کے نشان کو کہتے ہیں.چنانچہ لغت عرب میں اقسَمَ الرَّجُلُ اُس وقت کہتے
ہیں جب کوئی شخص اپنے لئے کوئی ایسی علامت مقرر کرلے جس سے وہ پہچانا جا سکے اور عوام
الناس اُسے دوسرے اشخاص سے الگ سمجھ سکیں اور اہلِ زبان کے نزدیک وسُم کے لفظ سے
ى سِمَةُ الْبَعِيرِ اور وِسَامُ الْبَعِيرِ مشتق ہے.جس کے معنے اونٹ پر داغ دے کر کوئی شکل
بنانے کے ہیں تا وہ شکل اُس کی شناخت میں محمد ہو.اور اسی لفظ و سم سے اہلِ عرب کا یہ محاورہ
ہے إِنِّي تَوَسَمْتُ فِيهِ الْخَيْرَ وَمَا رَأَيْتُ الضّيرِ یعنی میں نے اس کے چہرے پر غور کیا اور
اس پر کوئی شر کی علامت نہ دیکھی اور نہ ہی میں نے اس کی زندگی میں بدی کا کوئی نشان پایا.پھر اسی لفظ و سم سے وسمی کا لفظ نکلا ہے جس کے معنی موسم بہار کی پہلی بارش کے ہیں کیونکہ
جب وہ برستی ہے تو زمین پر پانی بہنے کے نشان بناتی ہے جیسے چشمے اپنے بہنے سے نشان بناتے
ہیں.اسی طرح آرضٌ مَّوْسُومَةٌ زمین کو اس وقت کہتے ہیں جب اس پر موسم بہار کی پہلی
بارش بر وقت بر سے اور بہہ کر کسانوں کے دلوں کو تسکین دے.پھر اسی لفظ وَسُم سے موسم
نکلا ہے جیسے مَوْسِمُ الْحَج ہے اور مَوْسِمُ السُّوق اور دوسرے مواسم ہیں.کیونکہ یہ ایسے
مواقع ہیں جن میں کسی نہ کسی مقصد کے لئے لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے اور میسم کا لفظ بھی وَسُم
سے ہی مشتق ہے جس کا اطلاق حسن و جمال پر ہوتا ہے اور اکثر حالتوں میں خوبصورت عورتوں
کے بارے میں استعمال ہوتا ہے.عربی زبان اور عرب شعراء کے دیوانوں کی چھان بین کرنے
سے یہ بات ثابت ہوگئی ہے کہ وہ اس لفظ کو زیادہ ترخیر کے مواقع پر ہی استعمال کرتے
تھے، خواہ وہ دنیا کی خیر ہو یا دین کی اور آپ جانتے ہیں کہ عوام الناس کے نزدیک کسی چیز کا
اسم وہ ہوتا ہے جس سے وہ چیز پہچانی جاتی ہے لیکن خواص اور اہل علم کے نزدیک اسم شے کی اصل
حقیقت کے لئے بطور ظل کے ہے بلکہ یہ امر یقینی ہے کہ اشیاء کے جو نام اللہ تعالیٰ کی طرف
سے ہیں یہ تمام نام ان چیزوں کے لئے ان کی نوعی صورتوں کی حیثیت رکھتے ہیں اور یہ نام معانی
اور علوم حکمیہ کے پرندوں کے لئے بمنزلہ گھونسلوں کے ہیں.اور اس بابرکت آیت میں اللہ،
رحمان اور رحیم ناموں کا یہی حال ہے.کیونکہ ان میں سے ہر ایک اپنے خصائص اور اپنی مخفی
46
Page 55
ماہیت پر دلالت کرتا ہے.اور اللہ اس ذات الہی کا نام ہے جو تمام کمالات کی جامع ہے.اور اس جگہ الر حمن اور
الرَّحِيم دونوں اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ یہ دونوں صفتیں اللہ کے لئے ثابت ہیں جو ہر قسم
کے جمال اور جلال کا جامع ہے.پھر لفظ الرحمن کے ایک اپنے بھی خاص معنی ہیں جو الرّحِیم
کے لفظ میں نہیں پائے جاتے اور وہ یہ ہیں کہ اذنِ الہی سے صفت آل محمن کا فیضان انسان اور
دوسرے حیوانات کو قدیم زمانہ سے حکمتِ الہیہ کے اقتضاء اور جوہر قابل کی قابلیت کے مطابق
پہنچتا رہا ہے.نہ کہ مساوی تقسیم کے طور پر اور اس صفت رحمانیت میں انسانوں یا حیوانوں کے
قویٰ کے کسب اور عمل اور کوشش کا کوئی دخل نہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا خالص احسان ہے جس
سے پہلے کسی کا کچھ عمل بھی موجود نہیں ہوتا اور یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک عام رحمت ہے جس
میں ناقص یا کامل شخص کی کوششوں کا کوئی دخل نہیں ہوتا.حاصل کلام یہ ہے کہ صفت رحمانیت کا فیضان کسی عمل کا نتیجہ نہیں ہے اور نہ کسی استحقاق کا
شمرہ ہے بلکہ یہ ایک خاص فضل ایزدی ہے جس میں فرمانبرداری یا نا فرمانی کا دخل نہیں
اور یہ فیضان ہمیشہ خدا تعالیٰ کی مشیت اور ارادہ کے ماتحت نازل ہوتا ہے.اس میں کسی
اطاعت، عبادت، تقویٰ اور زہد کی شرط نہیں.اس فیض کی بنا مخلوق کی پیدائش، اس کے اعمال،
اس کی کوشش اور اس کے سوال کرنے سے پہلے ہی رکھی گئی ہے.اس لئے اس فیض کے
آثار انسان اور حیوان کے وجود میں آنے سے پہلے ہی پائے جاتے ہیں اگر چہ یہ فیض تمام
مراتب وجود اور زمان و مکان اور حالتِ طاعت و عصیان میں جاری وساری رہتا ہے.کیا آپ
نہیں دیکھتے کہ خدا تعالیٰ کی رحمانیت نیکو کاروں اور ظالموں سب پر وسیع ہے اور آپ دیکھ
رہے ہیں کہ اس کا چاند اور اس کا سورج اطاعت گزاروں اور نافرمانوں کبھی پر چڑھتا ہے.اور
خدا تعالیٰ نے ہر چیز کو اس کے مناسب حال قومی کے ساتھ پیدا کیا ہے اور اس نے ان سب
کے معاملات کا ذمہ لیا ہے اور کوئی بھی جاندار نہیں مگر اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے خواہ وہ
آسمانوں میں ہو یا زمین میں.اسی نے ان کے لئے درخت پیدا کئے اور ان درختوں سے پھل
47
Page 56
پھول اور خوشبوئیں پیدا کیں اور یہ ایسی رحمت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی پیدائش سے
پہلے ہی ان کے لئے مہیا فرمایا.اس میں متقیوں کے لئے نصیحت اور یاد دہانی ہے.یہ عمتیں بغیر
کسی عمل اور بغیر کسی حق کے اس بے حد مہر بان اور عظیم خالق عالم کی طرف سے عطا ہوئی
ہیں.اور اس عالی بارگاہ سے ایسی ہی اور بھی بہت سی نعمتیں بخشی گئی ہیں جو شمار سے باہر ہیں.مثلاً
صحت قائم رکھنے کے ذرائع پیدا کرنا اور ہر بیماری کے لئے علاج اور دواؤں کا پیدا کرنا.رسولوں
کا مبعوث کرنا اور انبیاء پر کتابوں کا نازل کرنا یہ سب ہمارے رب ارحم الراحمین کی رحمانیت
ہے.یہ خالص فضل ہے جو کسی کام کرنے والے کے کام یا گریہ وزاری یا دُعا کے نتیجہ میں نہیں
ہے لیکن رحیمیت وہ فیض الہی ہے جو صفت رحمانیت کے فیوض سے خاص تر ہے.یہ فیضان
نوع انسانی کی تکمیل اور انسانی فطرت کو کمال تک پہنچانے کے لئے مخصوص ہے لیکن اس کے
حاصل کرنے کے لئے کوشش کرنا، عمل صالح بجالانا اور جذبات نفسانیہ کو ترک کرنا شرط
ہے.یہ رحمت پورے طور پر نازل نہیں ہوتی جب تک اعمال بجالانے میں پوری کوشش نہ
کی جائے اور جب تک تزکیہ نفس نہ ہو اور ریا کوگالی طور پر ترک کر کے خلوص کامل اور طہارتِ
قلب حاصل نہ ہو اور جب تک خدائے ذوالجلال کی خوشنودی حاصل کرنے کی خاطر موت کو
قبول نہ کر لیا جائے.پس مبارک ہیں وہ لوگ جنہیں ان نعمتوں سے حصہ ملا.بلکہ وہی اصل
انسان ہیں اور باقی لوگ تو چار پائیوں کی مانند ہیں.یہاں ایک مشکل سوال ہے جسے ہم اس جگہ مع جواب لکھتے ہیں تا کہ عقلمند اس میں غورو
فکر کر سکیں اور وہ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بسمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ میں اپنی تمام
صفات میں سے صرف دوصفات الرحمن اور الرحیم کو ہی اختیار کیا ہے اور کسی اور صفت
کا اس آیت میں ذکر نہیں کیا.حالانکہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ( یعنی اللہ ) تمام ان صفات کا ملہ کا
مستحق ہے جو مقدس صحیفوں میں مذکور ہیں.پھر کثرت صفات تلاوت کے وقت کثرت برکات
کو مستلزم ہے.پس بسم اللہ کی آیت کریمہ اللہ کی کثرت صفات کے بیان کے مقام اور مرتبہ کی
زیادہ حقدار اور سزاوار ہے اور حدیث نبوی میں ہرا ہم کام شروع کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا
48
Page 57
مستحسن قرار دیا گیا ہے نیز یہ آیت مسلمانوں کی زبانوں پر اکثر جاری رہتی ہے.اور خدائے
عزیز کی کتاب قرآن کریم میں بڑی کثرت سے دہرائی گئی ہے.تو پھر کس حکمت اور مصلحت
کے ماتحت اس مبارک آیت میں خدا تعالیٰ کی دوسری صفات درج نہیں کی گئیں؟
اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ ارادہ فرمایا کہ اپنے اسم اعظم کے ساتھ
انہی دو صفات کا ذکر کرے جو اس کی تمام صفات عظیمہ کا پورا پورا خلاصہ ہیں.اور وہ دونوں
صفات الرحمن اور الرّحِیم ہیں.چنانچہ عقل سلیم بھی اسی کی طرف راہنمائی کرتی ہے.کیونکہ خدا تعالیٰ نے اس دنیا پر کبھی بطور محبوب اور کبھی بطور محب تجلی فرمائی ہے اور اس نے
ان دونوں صفات کو ایسی روشنی بنایا ہے جو آفتاب ربوبیت سے عبودیت کی زمین پر نازل ہوتی
ہے.پس کبھی تو خدا تعالیٰ محبوب بن جاتا ہے اور بندہ اس محبوب کا محب اور کبھی بندہ محبوب بن
جاتا ہے اور خدا تعالیٰ اس کا محب ہوتا ہے اور بندہ کو مطلوب کی طرح بنالیتا ہے.اس میں کوئی
شک و شبہ نہیں کہ انسانی فطرت جس میں محبت ، دوستی اور سوز دل ودیعت کیا گیا ہے چاہتی
ہے کہ اس کا کوئی محبوب ہو جو اسے اپنی تجلیات جمالیہ اور نعمتوں اور عطایا سے اپنی طرف کھینچے اور
یہ کہ اس کا کوئی ایسا غم خوار دوست ہو جو خوف اور پریشان حالی کے وقت اس کا ساتھ دے وہ
اس کے اعمال کو ضائع ہونے سے بچائے اور اس کی امیدوں کو پورا کرے.پس خدا تعالیٰ
نے ارادہ کیا کہ جو کچھ انسان کی فطرت تقاضا کرتی ہے وہ اسے عطا کرے اور اپنی وسیع بخشش
کے طفیل اس پر اپنی نعمتوں کو پورا کرے.سو اُس نے اپنی انہی دو صفات الرحمن اور
الرّحیم کے ساتھ اس پر تجلی فرمائی.اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ دونوں صفات ربوبیت اور عبودیت کے درمیان ایک واسطہ
ہیں اور انہی دونوں کے ذریعہ انسانی معرفت اور سلوک کا دائرہ مکمل ہوتا ہے.ان دونوں کے
علاوہ خدا تعالیٰ کی باقی تمام صفات انہی دو صفتوں کے انوار میں شامل ہیں اور ان سمندروں کا ایک
قطرہ ہیں.پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے جس طرح اپنے لئے چاہا ہے کہ وہ نوع انسان کے لئے
محبوب اور محب بنے اسی طرح اُس نے اپنے کامل بندوں کے لئے چاہا کہ وہ بھی دوسرے بنی نوع
49
Page 58
انسان کے لئے اپنے اخلاق اور سیرت کے لحاظ سے اس کی ذات والا صفات کا پرتو ہوں اور ان
دونوں صفات کو اپنا لباس اور پوشش بنالیں تا عبودیت ربوبیت کے اخلاق کا جامہ پہن
لے.اور انسان کے (روحانی) نشو و نما میں کوئی نقص باقی نہ رہ جائے.پس اُس نے انبیاء اور
مرسلین کو پیدا کیا اور ان میں سے بعض کو اپنی صفت رحمانیت کا اور بعض کو اپنی صفت رحیمیت کا
مظہر بنایا تا کہ وہ محبوب بھی ہوں اور محب بھی اور اس کے فضل عظیم کے ساتھ آپس میں محبت سے
زندگی بسر کریں اُس نے ان میں سے بعض کو محبوبیت کی صفت سے حصہ وافر عطا فرمایا اور بعض
دوسروں کو صفت محبیت کا بہت سا حصہ دیا.اور اسی کا خدا تعالیٰ نے اپنے وسیع فضل اور دائمی
کرم سے ارادہ فرمایا.اور جب ہمارے آقاسید المرسلین و خاتم النبیین محمدصلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ
آیا تو اللہ تعالیٰ کی پاک ذات نے ارادہ فرمایا کہ ان دونوں صفات کو ایک ہی شخصیت میں جمع
کردے.چنانچہ اس نے آنحضرت کی ذات میں (آپ پر ہزاروں ہزار درود اور سلام ہو) یہ
دونوں صفات جمع کر دیں.یہی وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ کے شروع میں صفت محبوبیت
اور صفت محبیت کا خاص طور پر ذکر کیا ہے تا اس سے خدا تعالیٰ کے اس ارادہ کی طرف اشارہ
ہو اور اس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد اور احمد رکھا.جیسا کہ اُس نے اس آیت میں
اپنا نام الرحمن اور الرحیم رکھا.پس یہ بات اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ ان دونوں صفات کا
ہمارے آقا فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کوئی جامع وجود نہیں.اور آپ کو معلوم ہے کہ
یہ دونوں صفات خدا تعالیٰ کی صفات میں سے سب سے بڑی صفات ہیں بلکہ یہ اس کے تمام
صفاتی ناموں کے خلاصوں کا خلاصہ اور حقیقتوں کی نچوڑ ہیں.یہ ہر اس شخص کے کمال کا معیار ہیں
جو کمال کا طالب ہے اور اخلاقِ الہیہ کا رنگ اختیار کرتا ہے.پھر ان دونوں صفات میں سے کامل حصہ صرف ہمارے نبی سلسلہ نبوت کے خاتم صلی اللہ
علیہ وسلم کو ہی دیا گیا ہے کیونکہ آپ کو پروردگار دو عالم کے فضل سے ان دونوں صفات کی طرح دو
نام دیئے گئے ہیں جن میں سے پہلا محمد ہے اور دوسرا احمد.پس اسم محمد نے صفت الرحمن کی چادر
50
Page 59
پہنی اور جلال اور محبوبیت کے لباس میں جلوہ گر ہوا اور اپنی نیکی اور احسان
کی بناء پر بار بار تعریف
بھی کیا گیا.اور اسم احمد نے خدا تعالیٰ کے فضل سے جو مومنوں کی مدد اور نصرت کا متولی ہے
رحیمیت، محبیت اور جمال کے لباس میں تجلی فرمائی.پس ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
دونوں نام محمد اور احمد) ہمارے رب محسن کی دونوں صفتوں (الرحمان، الرحیم) کے مقابلہ
میں منعکسہ صورتوں کی طرح ہیں جن کو دو مقابل کے آئینے ظاہر کرتے ہیں.اور اللہ تعالیٰ نے آیت دَنَا فَتَدَلَّى (النجم 8) اور آیت قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ ادْنٰی
(النجم (9) میں اسی ( محبوبیت اور محبیت کے مضمون ) کی طرف اشارہ کیا ہے.پھر
چونکہ یہ گمان پیدا ہو سکتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جولوگوں کے مطاع اور اللہ تعالیٰ کے
بہت عبادت گزار ہیں پروردگار عالم کا ان دو صفات سے متصف کرنا لوگوں کو شرک کی طرف
مائل کر سکتا ہے.جیسا کہ ایسے ہی اعتقاد کی بنا پر حضرت عیسی کو معبود بنا لیا گیا.سو اللہ تعالیٰ
نے ارادہ کیا کہ وہ امت مرحومہ کو بھی ( علی حسب مراتب ) ظلی طور پر ان دونوں صفات کا
وارث بنادے.تا یہ دونوں نام امت کیلئے برکات جاریہ کا موجب بنیں اور تا صفات الہیہ میں کسی
خاص بندہ کے شریک ہونے کا وہم بھی دور ہو جائے.پس اللہ تعالیٰ نے آپ کے صحابہ اور بعد
آنے والے مسلمانوں کو رحمانی اور جلالی شان کی بنا پر اسم محمد کا مظہر بنایا اور انہیں غلبہ عطا
فرمایا.اور متواتر عنایات سے ان کی مدد کی اور مسیح موعود کو اسم احمد کا مظہر بنایا اور اُسے رحیمی اور
جمالی صفات کے ساتھ مبعوث فرمایا اور اس کے دل میں رحمت اور شفقت رکھ دی اور اُسے بلند
اخلاق فاضلہ کے ساتھ آراستہ کیا....اسم عیسی اور اسم احمد اپنی ماہیت میں ایک ہی ہیں اور
طبیعت کے لحاظ سے ایک دوسرے سے مطابقت رکھتے ہیں اور اپنی کیفیت کے لحاظ سے یہ نام
جمال اور ترک قتال پر دلالت کرتے ہیں لیکن اسم محمد قہر اور جلال کا نام ہے اور یہ ہر دو نام محمد
اور احمد، رحمن و رحیم کے لئے بطور ظل کے ہیں....پھر جب صحابہ کرام خدائے بخشندہ کی طرف سے اسم محمد کے وارث ہوئے اور انہوں
51
Page 60
نے جلال الہی کو ظاہر کیا اور ظالموں کو چوپایوں اور مویشیوں کی طرح قتل کیا.اسی طرح مسیح
موعود اسم احمد کا وارث ہوا جو مظہر رحیمیت و جمال ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ نام اس کے لئے
اور اس کے متبعین کے لئے جو اس کی آل کی طرح بن گئے اختیار کیا.پس مسیح موعود اپنی
جماعت سمیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی صفت رحیمیت اور احمدیت کا مظہر ہے.تا خدا
کا قول وَآخَرِيْنَ مِنْهُمُ ( الجمعة 4) پورا ہو ( یعنی صحابہ جیسی ایک اور قوم بھی ہے جو ابھی
ان سے نہیں ملی ).اور الہی ارادوں کو پورا ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا.نیز رسول مقبول
صلی اللہ علیہ وسلم کے مظاہر پیدا ہونے کی حقیقت پوری طرح واضح ہو جائے.صفتِ
رحمانیت ورحیمیت کو بسم اللہ کے ساتھ وابستہ کرنے کی یہی وجہ ہے تا وہ محمد واحمد دونوں ناموں
پر اور ان دونوں کے آئندہ آنے والے مظاہر پر دلالت کرے یعنی صحابہ اور مسیح موعود پر جو
رحیمیت اور احمدیت کے لباس میں آنے والے تھے.چونکہ ہمارے نبی خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء برگزیدوں کے برگزیدہ اور
اللہ تعالیٰ کی جناب میں سب لوگوں سے زیادہ محبوب ہیں.اس لئے اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ
ظلی طور پر آپ میں اپنی یہ دونوں بڑی صفات جمع کردے.پس آپ کو محمد اور احمد کے نام عطا
کئے تا یہ دونوں نام صفتِ رحمانیت اور صفت رحیمیت کے لئے بمنزلہ طیل کے ہوں.اسی لئے
اس نے اپنے قول إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْن میں اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ
کامل عبادت گزار کو رب العالمین کی صفات عطا کی جاتی ہیں جبکہ وہ فنافی اللہ عابدوں کے مقام
تک پہنچ جائے.اور آپ کو معلوم ہے کہ اخلاق الہیہ کا ہر کمال اللہ تعالیٰ کے رحمان و رحیم
ہونے پر منحصر ہے.اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں صفات کو بسم اللہ کے ساتھ مخصوص کر
دیا.اور آپ کو یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ محمد اور احمد نام "الرحمان الرحیم " کے مظہر ہیں اور ہر
کمال جو ان دونوں صفات الہیہ میں مخفی تھا وہ علیم و حکیم خدا کی طرف سے ( محمد اور احمد کے )
دونوں ناموں میں ودیعت کر دیا گیا ہے پس بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں ناموں
52
Page 61
( محمد اور احمد ) کو اپنی دونوں صفات کے ظل اور اپنی دونوں سیرتوں کے مظہر ٹھہرایا ہے تاکہ
رحمانیت اور رحیمیت کی حقیقت کو محمدیت اور احمدیت کے آئینہ میں دکھائے.پھر جبکہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے کامل افراد جو آنحضرت کی روحانیت کے اجزاء اور
حقیقت نبویہ کے اعضاء کی طرح ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ اس نبی معصوم صلی اللہ
علیہ وسلم کے آثار کو باقی رکھنے کے لئے انہیں ( امت کے کامل افراد کو ) بھی اسی طرح ان
دونوں ناموں کا وارث بنائے جیسے اس نے انہیں علوم نبویہ کا وارث بنایا ہے.پس اُس نے
صحابہ کو اسم محمد کے ظن کی ذیل میں داخل کر دیا جو اسم کے جلال کا مظہر ہے اور مسیح موعود کو اسم
احمد کے ذیل میں داخل کر دیا جو جمال کا مظہر ہے.اور ان سب نے اس دولت کو محض ظلیت
کے طور پر پایا ہے.پس حقیقت کی رُو سے اس مقام پر خدا تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں اور ان دو
ناموں کی تقسیم سے اللہ تعالیٰ کی غرض یہی تھی کہ وہ امت کو تقسیم کرے اور اس کے دو گروہ
کردے.پس اس نے ان میں سے ایک گروہ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام مظہر جلال کی مانند بنایا
اور وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں جنہوں نے جہاد کے لئے اپنے آپ کو پیش کر دیا
تھا اور ایک گروہ کو حضرت عیسی علیہ السلام مظہر جمال کی مانند بنایا اور ان کو دل کا حلیم بنایا.ان
کے سینوں میں صلح جوئی ودیعت کی اور ان کو اعلیٰ اخلاق پر قائم کیا اور امت کا یہ گروہ مسیح موعود اور اس
کے متبعین ہیں خواہ مرد ہوں یا عورتیں.پس جو کچھ حضرت موسیٰ نے فرمایا تھا وہ بھی اور جو
حضرت عیسیٰ ( علیہما السلام) نے فرمایا تھا وہ بھی پورا ہوا اور اس طرح خدائے قادر کا وعدہ بھی
پورا ہو گیا کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آشدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ (الفتح (30) کہہ کر ان
صحابہ کے متعلق پیشگوئی فرمائی تھی جو ہمارے نبی محمد مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم محمد کے مظہر
اور خدائے قہار کے جلال کا انعکاس تھے.اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صحابہ کے ایک
دوسرے گروہ اور ان ابرار کے امام کے متعلق اپنے قول كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطة (الفتح
30) میں اس روئیدگی کی پیشگوئی فرمائی تھی جو کسانوں کو خوش کرتی ہے.یعنی اس مسیح کے متعلق
53
Page 62
جور تم کرنے والے اور پردہ پوش (اسم) احمد کا مظہر اور رحیم وغفار خدا کے جمال کا منبع ہے.پس
موسیٰ و عیسیٰ ہر دو نے پیشگوئی میں ایسی صفات کی خبر دی تھی جو ان کی اپنی صفات ذاتیہ سے
مناسبت رکھتی ہیں.اور ہر ایک نے اس جماعت کو ( پیشگوئی کے لئے ) چنا جن کے اخلاق
اس کے اپنے پسندیدہ اخلاق کے مشابہ تھے.پس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے الفاظ
اشداء عَلَى الْكُفَّارِ (الفتح (30) میں ان صحابہ کی طرف اشارہ فرمایا جنہوں نے ہمارے
نبی اکرم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی اور انہوں نے جنگ کے میدانوں میں سختی
و مضبوطی کا مظاہرہ کیا.اللہ تعالیٰ کے جلال کو سیف قاطع کے ذریعہ ظاہر کیا اور خدائے قہار کے
رسول کے اسم محمد کے ظل بن گئے.آپ پر اللہ تعالی ، اہل آسمان اور اہل زمین میں سے
راستبازوں اور نیکوکاروں کا صلوۃ اور سلام ہو.اور حضرت عیسی علیہ السلام نے اپنے قول
كَزَرْعٍ اَخْرَجَ شَطه الفتح (30 سے آخَرِينَ مِنْهُمْ (الجمعة4) کی قوم اور ان
کے امام مسیح کی طرف اشارہ کیا بلکہ اس کے احمد نام کا صراحت سے ذکر کر دیا.اور اس مثال
سے جو قرآن کریم میں آئی ہے آپ نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ مسیح موعود کسی
بہت سخت چیز کی طرح نہیں بلکہ صرف نرم و نازک سبزہ کی طرح ظاہر ہوگا.پھر یہ بھی قرآن
کریم کے عجائبات میں سے ہے کہ اس نے احمد نام کا ذکر حضرت عیسی علیہ السلام سے نقل کیا
اور محمد نام کا ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نقل کیا تا کہ پڑھنے والے کو معلوم ہو جائے کہ
جلالی نبی یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ نام چنا جو ان کی اپنی شان کے مطابق ہے یعنی
اسم محمد جو جلالی نام ہے اور اسی طرح حضرت عیسی علیہ السلام نے احمد نام چنا جو جمالی نام ہے
کیونکہ وہ خود جمالی نبی تھے اور انہیں شدت اور جنگ سے کوئی حصہ نہیں دیا گیا تھا.خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان دونوں میں سے ہر ایک نبی نے اپنے اپنے کامل مثیل کی طرف
اشارہ کیا.پس (اے مخاطب) اس نکتہ کو یادرکھ کیونکہ یہ تجھے شکوک وشبہات سے نجات دے
گا اور جلال اور جمال کے دونوں پہلوؤں کو آشکار کرے گا اور پردہ اٹھا کر حقیقت کو واضح کر
54
Page 63
دے گا اور جب تو اس بیان کو قبول کرلے تو ہر دجال ( کے شر ) سے خدا تعالیٰ کی حفظ وامان میں
آ جائے گا اور ہر گمراہی سے نجات پا جائے گا.اعجاز المسیح.روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 89-128)
الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ مُلِكِ يَوْمِ الدِّينِ
الحمد لله - تمام محامد اس ذات معبود برحق مستجمع جمیع صفات کاملہ کو ثابت ہیں جس کا
نام اللہ ہے...قرآن شریف کی اصطلاح میں اللہ اس ذات کامل کا نام ہے کہ جو معبود
برحق اور مجمع جمیع صفات کا ملہ اور تمام رزائل سے منزہ ہ اور واحد لاشریک اور مبدء جمیع فیوض ہے.کیونکہ خدائے تعالیٰ نے اپنے کلام پاک قرآن شریف میں اپنے نام اللہ کو تمام دوسرے اسماء و
صفات کا موصوف ٹھہرایا ہے اور کسی جگہ کسی دوسرے اسم کو یہ رتبہ نہیں دیا.پس اللہ کے اسم کو
بوجہ موصوفیت تامہ ان تمام صفتوں پر دلالت ہے جن کا وہ موصوف ہے اور چونکہ وہ جمیع اسماء اور
صفات کا موصوف ہے اس لئے اس کا مفہوم یہ ہوا کہ وہ جمیع صفات کاملہ پر مشتمل ہے.پس خلاصه مطلب الحمد للہ کا یہ نکلا کہ تمام اقسام حمد کے کیا باعتبار ظاہر کے اور کیا باعتبار باطن
کے اور کیا باعتبار ذاتی کمالات کے اور کیا باعتبار قدرتی عجائبات کے اللہ سے مخصوص ہیں اور
اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں.اور نیز جس قدر محامد صحیحہ اور کمالاتِ تامہ کو عقل کسی عاقل
کی سوچ سکتی ہے یا فکر کسی متفکر کا ذہن میں لا سکتا ہے.وہ سب خوبیاں اللہ تعالیٰ میں موجود
ہیں.اور کوئی ایسی خوبی نہیں کہ عقل اس خوبی کے امکان پر شہادت دے.مگر اللہ تعالی بد قسمت
انسان کی طرح اس خوبی سے محروم ہو.بلکہ کسی عاقل کی عقل ایسی خوبی پیش ہی نہیں کر سکتی کہ جو
خدا میں نہ پائی جائے.جہاں تک انسان زیادہ سے زیادہ خوبیاں سوچ سکتا ہے وہ سب اس میں
موجود ہیں اور اس کو اپنی ذات اور صفات اور محامد میں من کل الوجوہ کمال حاصل ہے اور رذائل
سے بکلّی منڈہ ہے.(براہین احمدیہ چہار حصص ، روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 435 436 حاشیہ نمبر 11 )
واضح ہو کہ حمد اس تعریف کو کہتے ہیں جو کسی مستحق تعریف کے اچھے فعل پر کی جائے نیز
55
Page 64
ایسے انعام کنندہ کی مدح کا نام ہے جس نے اپنے ارادہ سے انعام کیا ہو.اور اپنی مشیت کے
مطابق احسان کیا ہو.اور حقیقت حمد کما حقہ صرف اسی ذات کے لئے متحقق ہوتی ہے جو تمام فیوض و
انوار کا مبدء ہواور علی وجہ البصیرت کسی پر احسان کرے نہ کہ غیر شعوری طور پر یا کسی مجبوری سے.اور
حمد کے یہ معنی صرف خدائے خبیر و بصیر کی ذات میں ہی پائے جاتے ہیں.اور وہی محسن ہے اور اول و
آخر میں سب احسان اسی کی طرف سے ہیں.اور سب تعریف اسی کے لئے ہے اس دنیا میں بھی اور
اُس دنیا میں بھی اور ہر حمد جو اس کے غیروں کے متعلق کی جائے اس کا مرجع بھی وہی ہے.پھر یہ بھی
یادر ہے کہ لفظ حمد جو اس آیت میں اللہ ذوالجلال کی طرف سے استعمال ہوا ہے مصدر ہے جو بطور
مبنى للمعلوم اور مبنی للمجھول ہے.یعنی فاعل اور مفعول دونوں کے لئے ہے.اور اس
کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کامل طور پر تعریف کیا گیا اور تعریف کرنے والا ہے.اور اس بیان پر
دلالت کرنے والا قرینہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حمد کے بعد ایسی صفات کا ذکر فرمایا ہے جو اہل
عرفان کے نزدیک ان معنی کو مستلزم ہیں.اور اللہ تعالیٰ نے لفظ حمد میں ان صفات کی طرف اشارہ
فرمایا ہے کہ جو اس کے ازلی ٹور میں پائی جاتی ہیں.اعجاز المسیح.روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 129-130)
حمد اس تعریف کو کہتے ہیں جو کسی صاحب اقتدار شریف ہستی کے اچھے کاموں پر اس کی
تعظیم و تکریم کے ارادہ سے زبان سے کی جائے اور کامل ترین حمد رب جلیل سے مخصوص ہے اور ہر
قسم کی حمد کا مرجع خواہ وہ تھوڑی ہو یا زیادہ ہمارا وہ ربّ ہے جو گمراہوں کو ہدایت دینے والا اور
ذلیل لوگوں کو عزت بخشنے والا ہے.اور وہ محمودوں کا محمود ہے ( یعنی وہ ہستیاں جو خود قابل حمد ہیں وہ
سب اس کی حمد میں لگی ہوئی ہیں).اکثر علماء کے نزدیک لفظ شکر حمد سے اس پہلو میں فرق رکھتا
ہے کہ وہ ایسی صفات سے مختص ہے کہ جو دوسروں کو فائدہ پہنچانے والی ہوں اور لفظ مدح لفظ حمد
سے اس بات میں مختلف ہے کہ مدح کا اطلاق غیر اختیاری خوبیوں پر بھی ہوتا ہے.اور یہ امر صیح و
بلیغ علماء اور ماہر ادباء سے مخفی نہیں.اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کو حمد سے شروع کیا ہے نہ کہ شکر اور مدح سے کیونکہ لفظ حمد
56
Page 65
ان دونوں الفاظ کے مفہوم پر پوری طرح حاوی ہے.اور وہ ان کا قائمقام ہوتا ہے مگر اس میں
اصلاح ، آرائش اور زیبائش کا مفہوم ان سے زائد ہے.چونکہ کفار بلا وجہ اپنے بتوں کی حمد کیا
کرتے تھے اور وہ ان کی مدح کے لئے حمد کے لفظ کو اختیار کرتے تھے اور یہ عقیدہ رکھتے تھے
کہ وہ معبود تمام عطایا اور انعامات کے سرچشمہ ہیں اور سخیوں میں سے ہیں.اسی طرح ان کے
مردوں کی ماتم کرنے والیوں کی طرف سے مفاخر شماری کے وقت بلکہ میدانوں میں بھی اور
ضیافتوں کے مواقع پر بھی اسی طرح حمد کی جاتی تھی جس طرح اس رازق، متولی اور ضامن
اللہ تعالیٰ کی حمد کی جانی چاہئے.اس لئے یہ (الحمد للہ) ایسےلوگوں اور دوسرے تمام مشرکوں کی
تردید ہے اور فراست سے کام لینے والوں کے لئے ( اس میں ) نصیحت ہے.اور ان الفاظ میں
اللہ تعالیٰ بت پرستوں، یہودیوں، عیسائیوں اور دوسرے تمام مشرکوں کو سرزنش کرتا ہے.گویا
وہ یہ کہتا ہے کہ اے مشرکو! تم اپنے شرکاء کی کیوں حمد کرتے ہو اور اپنے بزرگوں کی تعریف بڑھا
چڑھا کر کیوں کرتے ہو؟ کیا وہ تمہارے رب ہیں جنہوں نے تمہاری اور تمہاری اولاد کی
پرورش کی ہے یا وہ ایسے رحم کرنے والے ہیں جو تم پر ترس کھاتے ہیں اور تمہاری مصیبتوں کو دور
کرتے ہیں اور تمہارے دکھوں اور تکلیفوں کی روک تھام کرتے ہیں.یا جو بھلائی تمہیں مل چکی
ہے اس کی حفاظت کرتے ہیں.یا مصائب کی میل کچیل تمہارے وجود سے دھوتے ہیں اور
تمہاری بیماری کا علاج کرتے ہیں.کیا وہ جزا سزا کے دن کے مالک ہیں؟ نہیں بلکہ وہ تو اللہ
تعالی ہی ہے جو خوشیوں کی تعمیل کرنے، ہدایت کے اسباب مہیا کرنے، دُعائیں قبول کرنے
اور دشمنوں سے نجات دینے کے ذریعہ تم پر رحم فرماتا اور تمہاری پرورش کرتا ہے.اور اللہ تعالیٰ
نیکوکاروں کوضرور اجر عطا کرے گا.اور لفظ حمد میں ایک اور اشارہ بھی ہے اور وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے
(میرے) بندو! میری صفات سے مجھے شناخت کرو اور میرے کمالات سے مجھے پہچانو.میں
ناقص ہستیوں کی مانند نہیں بلکہ میری حمد کا مقام انتہائی مبالغہ سے حمد کرنے والوں سے بڑھ
57
Page 66
کر ہے اور تم آسمانوں اور زمینوں میں کوئی قابل تعریف صفات نہیں پاؤ گے جو تمہیں میری
ذات میں نہ مل سکیں.اور اگر تم میری قابل حمد صفات کو شمار کرنا چاہو تو تم ہر گز انہیں نہیں گن سکو
گے.اگر چہ تم کتنا ہی جان توڑ کر سوچو اور اپنے کام میں مستغرق ہونے والوں کی طرح ان صفات
کے بارہ میں کتنی ہی تکلیف اٹھاؤ.خوب سوچو! کیا تمہیں کوئی ایسی حمد نظر آتی ہے جو میری ذات
میں نہ پائی جاتی ہو؟ کیا تمہیں ایسے کمال کا سراغ ملتا ہے جو مجھ سے اور میری بارگاہ سے بعید ہو؟
اور اگر تم ایسا گمان کرتے ہو تو تم نے مجھے پہچانا ہی نہیں اور تم اندھوں میں سے ہو.بلکہ یقیناً میں
( اللہ تعالی ) اپنی ستودہ صفات اور اپنے کمالات سے پہچانا جاتا ہوں اور میری موسلادھار بارش کا
پتہ میری برکات کے بادلوں سے ہوتا ہے.پس جن لوگوں نے مجھے تمام صفات کا ملہ اور تمام
کمالات کا جامع یقین کیا اور انہوں نے جہاں جو کمال بھی دیکھا اور اپنے خیال کی انتہائی پرواز
تک انہیں جو جلال بھی نظر آیا انہوں نے اُسے میری طرف ہی نسبت دی.اور ہر عظمت جو اُن
کی عقلوں اور نظروں میں نمایاں ہوئی اور ہر قدرت جو ان کے افکار کے آئینہ میں انہیں دکھائی
دی انہوں نے اسے میری طرف ہی منسوب کیا.پس یہ ایسے لوگ ہیں جو میری معرفت کی
راہوں پر گامزن ہیں.حق ان کے ساتھ ہے اور وہ کامیاب ہونے والے ہیں.پس اللہ تعالیٰ
تمہیں عافیت سے رکھے.اُٹھو! خدائے ذوالجلال کی صفات کی تلاش میں لگ جاؤ اور
دانشمندوں اور غور و فکر کرنے والوں کی طرح ان میں سوچ و بچار اور امعان نظر سے کام لو.اچھی
طرح دیکھ بھال کرو اور کمال کے ہر پہلو پر گہری نظر ڈالو.اور اس عالم کے ظاہر میں اور اس کے
باطن میں اسے اس طرح تلاش کرو جیسے ایک حریص انسان بڑی رغبت سے اپنی خواہشات کی
تلاش میں لگا رہتا ہے.پس جب تم اس کے کمالِ تام کو پہنچ جاؤ اور اس کی خوشبو پالو تو گویا تم نے
اسی کو پالیا اور یہ ایسا راز ہے جو صرف ہدایت کے طالبوں پر ہی کھلتا ہے.پس یہ تمہارا رب اور
تمہارا آقا ہے جو خود کامل ہے اور تمام صفات کا ملہ اور محامد کا جامع ہے.اس کو وہی شخص پہچان
سکتا ہے جو سورۃ فاتحہ میں تدبر کرے اور دردمند دل کے ساتھ خدا تعالیٰ سے مدد مانگے.وہ
58
58
Page 67
لوگ جو اللہ تعالیٰ سے عہد باندھتے وقت اپنی نیت کو خالص کر لیتے ہیں اور اس سے عہد بیعت
باندھتے ہیں اور اپنے نفوس کو ہر قسم کے بغض اور کینہ سے پاک کرتے ہیں ان پر اس سورۃ
کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور وہ فوراً صاحب بصیرت بن جاتے ہیں.اور اس کے ساتھ ہی الحمد اللہ میں ایک یہ اشارہ بھی ہے کہ جو معرفت باری تعالیٰ
کے معاملہ میں اپنے بد اعمال سے بلاک ہوا یا اس کے سوا کسی اور کو معبود بنالیا تو سمجھو کہ وہ شخص
خدا تعالیٰ کے کمالات کی طرف سے اپنی توجہ پھیر لینے ، اس کے عجائبات کا نظارہ نہ کرنے اور
جو امور اس کی شایانِ شان ہیں ان سے باطل پرستوں کی طرح غفلت برتنے کے نتیجہ میں بلاک
ہو گیا.کیا تو نصاری کو نہیں دیکھتا کہ انہیں توحید کی دعوت دی گئی تو انہیں اسی بیماری نے بلاک
کیا اور ان کے گمراہ کرنے والے نفس اور پھسلا دینے والی خواہشات نے ان کے لئے
( یہ گمراہ کن ) خیال خوبصورت کر کے دکھا دیا اور انہوں نے ایک ( عاجز ) بندے کو خدا بنالیا اور
گمراہی اور جہالت کی شراب پی لی.اللہ تعالیٰ کے کمال اور اس کی صفات ذاتیہ کو بھول گئے اور
اس کے لئے بیٹے اور بیٹیاں تراش لیں اگر وہ اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کے شایان شان کمالات
پر گہری نظر ڈالتے تو ان کی عقل خطا نہ کرتی اور وہ بلاک ہونے والوں میں سے نہ ہو جاتے.پس یہاں
اللہ تعالیٰ نے اس طرف اشارہ فرمایا ہے کہ اللہ جل شانہ کی معرفت کے بارہ میں غلطی سے
بچانے والا قانون یہ ہے کہ اس کے کمالات میں پورا غور کیا جائے اور اس کی ذات کے لائق صفات
کی جستجو کی جائے اور ان صفات کا ورد کیا جائے جو ہر مادی عطیہ سے بہتر اور ہر مدد سے مناسب تر
ہیں اور اس نے اپنے کاموں سے جو صفات ثابت کی ہیں یعنی اس کی قوت اس کی طاقت اس کا
غلبہ اور اس کی سخاوت کا تصور کیا جائے.پس اس بات کو یا درکھو اور لا پر وامت بنو.اور جان لو کہ ربوبیت ساری کی ساری اللہ کے لئے ہے.اور رحمانیت ساری کی ساری اللہ
کے لئے ہے.اور رحیمیت ساری کی ساری اللہ کے لئے ہے اور جزا سزا کے دن کامل حکومت
اللہ کے لئے ہے.پس اے مخاطب اپنے پرورش کنندہ کی اطاعت سے انکار نہ کر اور موحد
59
Page 68
مسلمانوں میں سے بن جا.پھر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس طرف اشارہ فرمایا ہے کہ وہ ( پہلی صفت کے زوال
کے بعد کسی نئی صفت کو اختیار کرنے اور اپنی شان کے تبدیل ہونے اور کسی عیب کے لاحق
ہونے اور نقص کے بعد خوبی کے پانے سے پاک ہے.بلکہ اس کے لئے اول و آخر اور ظاہر
و باطن میں ابدالآباد تک حمد ثابت ہے.اور جو اس کے خلاف کہے وہ حق سے برگشتہ ہو کر کافروں
میں سے ہو گیا.یہ آیت نصاریٰ اور بت پرستوں کی تردید کرتی ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا حق پوری طرح ادا
نہیں کرتے اور اس کی روشنی کے پھیلنے کی امید نہیں رکھتے بلکہ اس پر اندھیرے کا پردہ پھیلا
دیتے ہیں.اور اس کو دُکھوں کی راہوں میں ڈال دیتے ہیں.اور اس کو پورے کمال سے دور
رکھتے ہیں.اور مخلوق میں سے ایک کثیر حصہ کو اس کا شریک قرار دیتے ہیں.الحمدُ لله کے الفاظ میں مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جب اُن سے سوال کیا
جائے اور اُن سے پوچھا جائے کہ اُن کا معبود کون ہے تو ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ یہ جواب
دے کہ میرا معبود وہ ہے جس کے لئے سب حمد ہے اور کسی قسم کا کوئی کمال اور قدرت ایسی نہیں
مگر وہ اس کے لئے ثابت ہے.پس تو بھولنے والوں میں سے نہ بن.اگر مشرکوں پر ایمان کی
کچھ بھی جھلک پڑ جاتی اور ان پر عرفان کی ہلکی سی بارش بھی ہو جاتی تو انہیں قیوم عالمین پر بدظنی
کرنا تباہ نہ کرتا.لیکن انہوں نے خدا تعالیٰ کو ایسے شخص کی مانند سمجھ لیا جو جوانی کے بعد بوڑھا
ہو گیا ہو اور اپنی بے نیازی کے بعد محتاج ہو گیا ہو اس پر بڑھاپا اور لاغری کی مصیبتیں اور قحط
کی سختیاں وارد ہوئی ہوں اور وہ مٹی میں مل گیا بلکہ تباہی کے کنارے جالگا ہو اور بالکل محتاج
ہو گیا ہو.کرامات الصادقین.روحانی خزائن جلد 7 صفحہ 106 - 110 )
اس سورۃ کو الحمد للہ سے شروع کیا گیا ہے جس کے یہ معنے ہیں کہ ہر ایک حمد اور
تعریف اس ذات کے لئے مسلّم ہے جس کا نام اللہ ہے.اور اس فقرہ الحمد للہ سے اس
60
Page 69
لئے شروع کیا گیا کہ اصل مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی عبادت رُوح کے جوش اور طبیعت کی
کشش سے ہو اور ایسی کشش جو عشق اور محبت سے بھری ہوئی ہو ہر گز کسی کی نسبت پیدا نہیں
ہوسکتی جب تک یہ ثابت نہ ہو کہ وہ شخص ایسی کامل خوبیوں کا جامع ہے جن کے ملاحظہ سے
بے اختیار دل تعریف کرنے لگتا ہے اور یہ تو ظاہر ہے کہ کامل تعریف دو قسم کی خوبیوں کے
لئے ہوتی ہے.ایک کمال محسن اور ایک کمال احسان اور اگر کسی میں دونوں خوبیاں جمع ہوں تو
پھر اُس کے لئے دل فدا اور شیدا ہو جاتا ہے.اور قرآن شریف کا بڑا مطلب یہی ہے کہ خدا
تعالی کی دونوں قسم کی خوبیاں حق کے طالبوں پر ظاہر کرے تا اُس بے مثل و مانند ذات کی
طرف لوگ کھینچے جائیں اور روح کے جوش اور کشش سے اُس کی بندگی کریں.اس لئے پہلی
سورۃ میں ہی یہ نہایت لطیف نقشہ دکھلانا چاہا ہے کہ وہ خدا جس کی طرف قرآن بلاتا ہے وہ کیسی
خوبیاں اپنے اندر رکھتا ہے.سو اسی غرض سے اس سورۃ کو الحمد للہ سے شروع کیا گیا جس
کے یہ معنے ہیں کہ سب تعریفیں اس کی ذات کے لئے لائق ہیں جس کا نام اللہ ہے.اور قرآن
کی اصطلاح کی رُو سے اللہ اُس ذات کا نام ہے جس کی تمام خوبیاں محسن و احسان کے کمال کے
نقطہ پر پہنچی ہوئی ہوں اور کوئی منقصت اُس کی ذات میں نہ ہو.قرآن شریف میں تمام صفات
کا موصوف صرف اللہ کے اسم کو ہی ٹھہرایا ہے تا اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ اللہ کا اسم تب
متحقق ہوتا ہے کہ جب تمام صفات کا ملہ اس میں پائی جائیں.پس جبکہ ہر ایک قسم کی خوبی اس
میں پائی گئی تو حسن اس کا ظاہر ہے.اسی محسن کے لحاظ سے قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کا نام
نور ہے.جیسا کہ فرمایا ہے اللهُ نُورُ السَّمَوتِ وَ الْأَرْضِ (النور (36) یعنی اللہ تعالیٰ
زمین و آسمان کا نُور ہے.ہر ایک نور اسی کے نور کا پر توہ ہے.اور احسان کی خوبیاں اللہ تعالیٰ
میں بہت ہیں جن میں سے چار بطور اصل الاصول ہیں اور ان کی ترتیب طبعی کے لحاظ سے پہلی
خوبی وہ ہے جس کو سورہ فاتحہ میں رَبُّ العلمین کے فقرہ میں بیان کیا گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ
خدا تعالیٰ کی ربوبیت یعنی پیدا کرنا اور کمال مطلوب تک پہنچانا تمام عالموں میں جاری وساری
61
Page 70
ہے یعنی عالم سماوی اور عالم ارضی اور عالم اجسام اور عالم ارواح اور عالم جواہر اور عالم اعراض اور
عالم حیوانات اور عالم نباتات اور عالم جمادات اور دوسرے تمام قسم کے عالم اس کی ربوبیت سے
پرورش پارہے ہیں یہاں تک کہ خود انسان پر ابتدا نطفہ ہونے کی حالت سے یا اس سے پہلے بھی
جو جو عالم موت تک یا دوسری زندگی کے زمانہ تک آتے ہیں وہ سب چشمہ ء ربوبیت سے فیض
یافتہ ہیں.پس ربوبیت الہی بوجہ اس کے کہ وہ تمام ارواح و اجسام و حیوانات و نباتات و
جمادات وغیرہ پر مشتمل ہے فیضانِ آعم سے موسوم ہے کیونکہ ہر ایک موجود اس سے فیض
پاتا ہے اور اسی کے ذریعہ سے ہر ایک چیز وجود پذیر ہے ہاں البتہ ربوبیت الہی اگر چہ ہر ایک
موجود کی موجد اور ہر ایک ظہور پذیر چیز کی مربی ہے لیکن بحیثیت احسان کے سب سے زیادہ
فائدہ اس کا انسان کو پہنچتا ہے کیونکہ خدا تعالیٰ کی تمام مخلوقات سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے.اس لئے انسان کو یاد دلایا گیا ہے کہ تمہارا خدا رب العلمین ہے تا انسان کی اُمید زیادہ ہو اور
یقین کرے کہ ہمارے فائدہ کے لئے خدا تعالیٰ کی قدرتیں وسیع ہیں اور طرح طرح کے عالم اسباب
ظہور میں لاسکتا ہے.دوسری خوبی خدا تعالیٰ کی جودوسرے درجہ کا احسان ہے جس کو فیضانِ عام
سے موسوم کر سکتے ہیں رحمانیت ہے جس کو سورۃ فاتحہ میں الرحمن کے فقرہ میں بیان کیا گیا
ہے اور قرآن شریف کی اصطلاح کی رُو سے خدا تعالیٰ کا نام رحمن اس وجہ سے ہے کہ اُس نے
ہر ایک جاندار کو جن میں انسان بھی داخل ہے اُس کے مناسب حال صورت اور سیرت بخشی
یعنی جس طرز کی زندگی اس کے لئے ارادہ کی گئی اس زندگی کے مناسب حال جن قوتوں اور
طاقتوں کی ضرورت تھی یا جس قسم کی بناوٹ جسم اور اعضاء کی حاجت تھی وہ سب اس کو عطا کئے
اور پھر اس کی بقا کے لئے جن جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ اس کے لئے مہیا کیں.پرندوں
کے لئے پرندوں کے مناسب حال اور چرندوں کے لئے چرندوں کے مناسب حال اور انسان
کے لئے انسان کے مناسب حال طاقتیں عنایت کیں اور صرف یہی نہیں بلکہ ان چیزوں کے
وجود سے ہزار ہا برس پہلے بوجہ اپنی صفت رحمانیت کے اجرام سماوی وارضی کو پیدا کیا تا وہ ان
62
Page 71
چیزوں کے وجود کی محافظ ہوں.پس اس تحقیق سے ثابت ہوا کہ خدا تعالیٰ کی رحمانیت میں کسی
کے عمل کا دخل نہیں بلکہ وہ رحمت محض ہے جس کی بنیادان چیزوں کے وجود سے پہلے ڈالی گئی.ہاں انسان کو خدا تعالیٰ کی رحمانیت سے سب سے زیادہ حصہ ہے کیونکہ ہر ایک چیز اس کی
کامیابی کے لئے قربان ہورہی ہے اس لئے انسان کو یاد دلایا گیا کہ تمہارا خدارحمن ہے.تیسری خوبی خدا تعالیٰ کی جو تیسرے درجہ کا احسان ہے رحیمیت ہے جس کو سورۃ فاتحہ میں
الرَّحِیمِ کے فقرہ میں بیان کیا گیا ہے اور قرآن شریف کی اصطلاح کے رُو سے خدا تعالیٰ
رحیم اس حالت میں کہلاتا ہے جبکہ لوگوں کی دُعا اور تضرر ع اور اعمالِ صالحہ کو قبول فرما کر آفات
اور بلاؤں اور تضییع اعمال سے ان کو محفوظ رکھتا ہے.یہ احسان دوسرے لفظوں میں فیض خاص
سے موسوم ہے اور صرف انسان کی نوع سے مخصوص ہے.دوسری چیزوں کو خدا نے دُعا اور
تضرع اور اعمال صالحہ کا ملکہ نہیں دیا مگر انسان کو دیا ہے.انسان حیوانِ ناطق ہے اور اپنی نطق
کے ساتھ بھی خدا تعالیٰ کا فیض پاسکتا ہے.دوسری چیزوں کو نطق عطا نہیں ہوا.پس اس جگہ
سے ظاہر ہے کہ انسان کا دُعا کرنا اس کی انسانیت کا ایک خاصہ ہے جو اس کی فطرت میں رکھا
گیا ہے اور جس طرح خدا تعالیٰ کی صفات ربوبیت اور رحمانیت سے فیض حاصل ہوتا ہے اسی
طرح صفت رحیمیت سے بھی ایک فیض حاصل ہوتا ہے.صرف فرق یہ ہے کہ ربوبیت اور
رحمانیت کی صفتیں دُعا کو نہیں چاہتیں کیونکہ وہ دونوں صفات انسان سے خصوصیت نہیں رکھتیں
اور تمام پرند چرند کو اپنے فیض سے مستفیض کر رہی ہیں بلکہ صفت ربوبیت تو تمام حیوانات اور
نباتات اور جمادات اور اجرامِ ارضی اور سماوی کو فیض رسان ہے اور کوئی چیز اس کے فیض سے
باہر نہیں.برخلاف صفت رحیمیت کے کہ وہ انسان کے لئے ایک خلعتِ خاصہ ہے.اور اگر
انسان ہو کر اس صفت سے فائدہ نہ اٹھا وے تو گویا ایسا انسان حیوانات بلکہ جمادات کے برابر ہے
جبکہ خدا تعالیٰ نے فیض رسانی کی چار صفت اپنی ذات میں رکھی ہیں اور رحیمیت کو جو انسان کی دُعا
کو چاہتی ہے خاص انسان کے لئے مقرر فرمایا ہے.پس اس سے ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ میں
ایک قسم کا وہ فیض ہے جو دعا کرنے سے وابستہ ہے اور بغیر دعا کے کسی طرح مل نہیں سکتا.یہ
63
Page 72
سنت اللہ اور قانونِ الہی ہے جس میں مختلف جائز نہیں یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہم السّلام اپنی اپنی
اُمتوں کے لئے ہمیشہ دعا مانگتے رہے.توریت میں دیکھو کہ کتنی دفعہ بنی اسرائیل خدا تعالی کو
ناراض کر کے عذاب کے قریب پہنچ گئے اور پھر کیونکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دُعا اور تضرع اور
ہے.سجدہ سے وہ عذاب ٹل گیا حالانکہ بار بار وعدہ بھی ہوتا رہا کہ میں ان کو بلاک کروں گا.اب ان تمام واقعات سے ظاہر ہے کہ دُعا محض لغو امر نہیں ہے اور نہ صرف ایسی عبادت
جس پر کسی قسم کا فیض نازل نہیں ہوتا.یہ ان لوگوں کے خیال ہیں کہ جو خدا تعالیٰ کا وہ قدر نہیں
کرتے جو حق قدر کرنے کا ہے اور نہ خدا کی کلام کو نظر عمیق سے سوچتے ہیں اور نہ قانونِ قدرت
پر نظر ڈالتے ہیں.حقیقت یہ ہے کہ دُعا پر ضرور فیض نازل ہوتا ہے جو ہمیں نجات بخشتا ہے.اسی کا نام فیض رحیمیت ہے جس سے انسان ترقی کرتا جاتا ہے.اسی فیض سے انسان ولایت
کے مقامات تک پہنچتا ہے اور خدا تعالیٰ پر ایسا یقین لاتا ہے کہ گویا آنکھوں سے دیکھ لیتا
مسئلہ شفاعت بھی صفت رحیمیت کی بناء پر ہے.خدا تعالیٰ کی رحیمیت نے ہی تقاضا
کیا کہ اچھے آدمی بُرے آدمیوں کی شفاعت کریں.چوتھا احسان خدا تعالیٰ کا جو قسم چہارم کی خوبی ہے جس کو فیضانِ آخص سے موسوم کر سکتے
ہیں مالکیت یوم الدین ہے جس کو سورہ فاتحہ میں فقرہ ملِكِ يَوْمِ الدِّينِ میں بیان
فرمایا گیا ہے اور اس میں اور صفت رحیمیت میں یہ فرق ہے کہ رحیمیت میں دُعا اور عبادت
کے ذریعہ سے کامیابی کا استحقاق قائم ہوتا ہے اور صفت مالکیت یوم الدین کے ذریعہ سے وہ
خمرہ عطا کیا جاتا ہے.اس کی ایسی ہی مثال ہے کہ جیسے ایک انسان گورنمنٹ کا ایک قانون
یاد کرنے میں محنت اور جدو جہد کر کے امتحان دے اور پھر اس میں پاس ہو جائے.پس
رحیمیت کے اثر سے کسی کامیابی کے لئے استحقاق پیدا ہو جانا پاس ہو جانے سے مشابہ ہے اور
پھر وہ چیز یا وہ مرتبہ میٹر آ جانا جس کے لئے پاس ہوا تھا اس حالت سے مشابہ انسان کے فیض
پانے کی وہ حالت ہے جو پر توہ صفت مالکیت یوم الدین سے حاصل ہوتی ہے.ان دونوں
صفتوں رحیمیت اور مالکیت یوم الدین میں یہ اشارہ ہے کہ فیض رحیمیت خدا تعالیٰ کے رحم
64
Page 73
سے حاصل ہوتا ہے.اور فیض مالکیت یوم الدین خدا تعالیٰ کے فضل سے حاصل ہوتا ہے اور
مالکئیت یوم الدین اگر چہ وسیع اور کامل طور پر عالم معاد میں متجلی ہو گی مگر اس عالم میں بھی اس
عالم کے دائرہ کے موافق یہ چاروں صفتیں تجلی کر رہی ہیں.ربوبیت عام طور پر ایک فیض کی
بنا ڈالتی ہے اور رحمانیت اس فیض کو جانداروں میں گھلے طور پر دکھلاتی ہے اور رحیمیت ظاہر
کرتی ہے کہ خط ممتد فیض کا انسان پر جا کر ختم ہو جاتا ہے اور انسان وہ جانور ہے جو فیض کو نہ
صرف حال سے بلکہ منہ سے مانگتا ہے اور مالکیت یوم الدین فیض کا آخری شمرہ بخشتی ہے.یہ
چاروں صفتیں دنیا میں ہی کام کر رہی ہیں مگر چونکہ دنیا کا دائرہ نہایت تنگ ہے اور نیز جہل اور
بے خبری اور کم نظری انسان کے شامل حال ہے اس لئے یہ نہایت وسیع دائرے صفاتِ اربعہ
کے اس عالم میں ایسے چھوٹے نظر آتے جیسے بڑے بڑے گولے ستاروں کے دُور سے صرف
نقطے دکھائی دیتے ہیں.لیکن عالم معاد میں پورا نظارہ ان صفات اربعہ کا ہوگا.اس لئے حقیقی اور
کامل طور پر یوم الدین وہی ہو گا جو عالم معاد ہے.اس عالم میں ہر ایک صفت ان صفاتِ
اربعہ میں سے دوہری طور پر اپنی شکل دکھائے گی یعنی ظاہری طور پر اور باطنی طور پر اس لئے
اس وقت یہ چار صفتیں آٹھ صفتیں معلوم ہوں گی.اسی کی طرف اشارہ ہے جو فرمایا گیا ہے کہ
اس دنیا میں چار فرشتے خدا تعالیٰ کا عرش اٹھا رہے ہیں اور اُس دن آٹھ فرشتے خدا تعالیٰ کا عرش
اٹھائیں گے.یہ استعارہ کے طور پر کلام ہے.چونکہ خدا تعالیٰ کی ہر صفت کے مناسب حال
ایک فرشتہ بھی پیدا کیا گیا ہے اس لئے چار صفات کے متعلق چار فرشتے بیان کئے گئے.اور
جب آٹھ صفات کی سجتی ہوگی تو ان صفات کے ساتھ آٹھ فرشتے ہوں گے.اور چونکہ یہ صفات
الوہیت کی ماہیت کو ایسا اپنے پر لئے ہوئے ہیں کہ گویا اُس کو اُٹھا رہے ہیں اس لئے
استعارہ کے طور پر اُٹھانے کا لفظ بولا گیا ہے.ایسے استعارات لطیفہ خدا تعالیٰ کی کلام میں
بہت ہیں جن میں روحانیت کو جسمانی رنگ میں دکھایا گیا ہے.غرض خدا تعالیٰ میں یہ چار
صفات عظیمہ ہیں جن پر ہر ایک مسلمان کو ایمان لانا چاہیے اور جو شخص دُعا کے ثمرات اور فیوض
65
Page 74
سے انکار کرتا ہے گویا وہ بجائے چارصفتوں کے صرف تین صفتوں کو مانتا ہے.ایام الصلح.روحانی خزائن جلد 14 صفحہ 247 -252)
رب - لسان العرب اور تاج العروس میں جو لغت کی نہایت معتبر کتابیں ہیں لکھا ہے
کہ زبان عرب میں رب کا لفظ سات معنوں پر مشتمل ہے اور وہ یہ ہیں.مالک.سید.مدثر.مربی - قیم - مُنْعِم - مُتَمِّم.چنانچہ ان سات معنوں میں سے تین معنی خدا تعالیٰ کی ذاتی
عظمت پر دلالت کرتے ہیں.منجملہ ان کے مالک ہے اور مالک لغت عرب میں اس کو
کہتے ہیں جس کا اپنے مملوک پر قبضہ تامہ ہو اور جس طرح چاہے اپنے تصرف میں لا سکتا ہو اور بلا
اشتراک غیر اس پر حق رکھتا ہو اور یہ لفظ حقیقی طور پر یعنی بلحاظ اس کے معنوں کے بجز خدا تعالیٰ
کے کسی دوسرے پر اطلاق نہیں پاسکتا کیونکہ قبضہ تامہ ہو اور تصرف تمام اور حقوق تامہ بجز خدا
تعالیٰ کے اور کسی کے لئے مسلم نہیں.منن الرحمان.روحانی خزائن جلد 9 صفحہ 152 ، 153 حاشیہ)
عالم کے معنے ہیں جس کے متعلق علم اور خبر دی جا سکے اور جو مدبر بالا رادہ کامل یگانہ
صانع پر دلالت کرے.اور جو ( یعنی عالم ) اس ( یکتا ہستی) پر ایمان لانے کے لئے طالب حق کو
مجبور کردے اور اس ( طالب) کو مومنوں ( کے گروہ ) تک پہنچا دے.کرامات الصادقین.روحانی خزائن جلد 7 صفحہ 110 )
عالمین سے مراد مخلوق کو پیدا کرنے والے خدا کے سوا ہر ہستی ہے خواہ وہ عالم ارواح
سے ہو عالم اجسام سے اور خواہ وہ زمینی مخلوق سے ہو یا سورج چاند اور ان کے علاوہ دیگر اجرام کی
مانند ( کوئی چیز ہو.پس تمام عالم جناب باری کی ربوبیت کے تحت داخل ہیں.اعجاز المسیح.روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 139-140)
یہاں خالقی العالمین نہیں فرمایا بلکہ رب العالمین فرمایا.اس لئے کہ بعض قومیں
ربوبیت کی منکر ہیں اور کہتی ہیں کہ ہم کو جو کچھ ملتا ہے ہمارے عملوں کے سبب سے ہی ملتا ہے مثلاً
اگر دودھ ملتا ہے تو اگر ہم کوئی گناہ کر کے گائے یا بھینس وغیرہ کے جون میں نہ جاتے تو دودھ ہی
نہ ہوتا.اور خلق چونکہ قطع برید کرنے کا نام ہے اس لئے اس موقعہ پر رب العالمین کو جو اس سے
66
Page 75
افضل تر ہے بیان فرمایا.الحکم جلد 4 نمبر 40 مؤرخہ 10 نومبر 1900 صفحہ 4)
وہ سچا اور کامل خدا جس پر ایمان لانا ہر ایک بندہ کا فرض ہے وہ رب العالمین ہے اور
اس کی ربوبیت کسی خاص قوم تک محدود نہیں اور نہ کسی خاص زمانہ تک اور نہ کسی خاص ملک
تک بلکہ وہ سب قوموں کا رب ہے اور تمام زمانوں کا رب ہے اور تمام مکانوں کا رب ہے اور
تمام ملکوں کا وہی رب ہے اور تمام فیضوں کا وہی سر چشمہ ہے اور ہر ایک جسمانی اور روحانی
طاقت اسی سے ہے اور اسی سے تمام موجودات پرورش پاتی ہیں اور ہر ایک وجود کا وہی سہارا
ہے.خدا کا فیض عام ہے جو تمام قوموں اور تمام ملکوں اور تمام زمانوں پر محیط ہو رہا ہے.یہ اس
لئے ہوا کہ تا کسی قوم کو شکایت کرنے کا موقع نہ ملے اور یہ نہ کہیں کہ خدا نے فلاں فلاں قوم پر
احسان کیا مگر ہم پر نہ کیا یا فلاں قوم کو اس کی طرف سے کتاب ملی تا وہ اس سے ہدایت پاویں مگر
ہم کو نہ ملی یا فلاں زمانہ میں وہ اپنی وحی اور الہام اور معجزات کے ساتھ ظاہر ہوامگر ہمارے زمانہ
میں مخفی رہا.پس اُس نے عام فیض دکھلا کر ان تمام اعتراضات کو دفع کر دیا اور اپنے ایسے وسیع
اخلاق دکھلائے کہ کسی قوم کو اپنے جسمانی اور روحانی فیضوں سے محروم نہیں رکھا اور نہ کسی زمانہ
کو بے نصیب ٹھہرایا.پیغام صلح.روحانی خزائن جلد 23 صفحہ 440 تا442)
خدا کا نام رب العلمین ہے.رب کے معنے پرورش کرنے والے کے ہیں.عالم روحانی
و جسمانی کی وہی پرورش کرتا ہے.اگر اس نے ایسے قومی انسان میں نہ رکھے ہوتے تو انسان ان
انعامات سے کہاں متمتع ہو سکتا.ایسا ہی روحانی ترقی بغیر اس کے فضل کے ناممکن ہے.البدر نمبر 25 جلد 7 مؤرخہ 25 جون 1908 صفحہ 3)
رَبُّ الْعَلَمِینَ کیسا جامع کلمہ ہے.اگر ثابت ہو کہ اجرام فلکی میں آبادیاں ہیں تب
بھی وہ آبادیاں اس کلمہ کے نیچے آئیں گی.کشتی نوح - روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 42 حاشیہ)
ملِكِ يَوْمِ الدین یعنی وہ خدا ہر ایک کی جزا اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے.اس کا کوئی
67
Page 76
ایسا کار پرداز نہیں جس کو اس نے زمین و آسمان کی حکومت سونپ دی ہو اور آپ الگ ہو بیٹھا
ہو اور آپ کچھ نہ کرتا ہو.وہی کار پرداز سب کچھ جزا سزاد یتا ہو یا آئندہ دینے والا ہو.اسلامی اصول کی فلاسفی.روحانی خزائن جلد 10 صفحہ 373)
م مالک ایک ایسا لفظ ہے جس کے مقابل پر تمام حقوق مسلوب ہو جاتے ہیں اور کامل
طور پر اطلاق اس لفظ کا صرف خدا پر ہی آتا ہے کیونکہ کامل مالک وہی ہے.جو شخص کسی کو
اپنی جان وغیرہ کا مالک ٹھہراتا ہے تو وہ اقرار کرتا ہے کہ اپنی جان اور مال وغیرہ پر میرا کوئی حق
نہیں اور میرا کچھ بھی نہیں سب مالک کا ہے.چشمہ معرفت روحانی خزائن جلد 23 صفحہ 23)
ہر ایک بدی کی سزا دینا خدا کے اخلاق عفو اور درگزر کے برخلاف ہے کیونکہ وہ مالک
ہے نہ صرف ایک مجسٹریٹ کی طرح جیسا کہ اُس نے قرآن شریف کی پہلی سورت میں ہی اپنا نام
مالک رکھا ہے اور فرمایا کہ ملِكِ يَوْمِ الدِّينِ یعنی خدا جزا سزا دینے کا مالک ہے اور ظاہر
ہے کہ کوئی مالک مالک نہیں کہلا سکتا جب تک دونوں پہلوؤں پر اس کو اختیار نہ ہو یعنی چاہیے تو
پکڑے اور چاہے تو چھوڑ دے.چشمه معرفت.روحانی خزائن جلد 23 صفحہ 24)
یہ دنیا ایک عالم امتحان ہے اس کے حل کرنے کے واسطے دوسرا عالم ہے.اس دنیا میں
جو تکالیف رکھی ہیں اس کا وعدہ ہے کہ آئندہ عالم میں خوشی دے گا.اگر اب بھی کوئی کہے کہ کیوں
ایسا کیا اور ایسا نہ کیا؟ اس کا یہ جواب ہے کہ وہ محکم اور مالکیت بھی تو رکھتا ہے.اُس نے جیسا
چاہا کیا.کسی کو اس کے اس کام پر اعتراض کی گنجائش اور حق نہیں.الحکم نمبر 35 جلد 12 مؤرخہ 30 رمئی 1908 ، صفحہ 5)
(انسان) گناہ سے تو جلالی رنگ اور ہیبت ہی سے بچ سکتا ہے جب یہ علم ہو کہ اللہ تعالیٰ
اس گناہ کی سزا میں شَدِيدُ الْعَذَابِ ہے اور مُلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ہے تو انسان پر ایک
ہیبت سی طاری ہو جائے گی جو اس کو گناہ سے بچالے گی.الحکم نمبر 45 جلد 5 مؤرخہ 10 دسمبر 1901، صفحہ 1)
ملِكِ يَوْمِ الدِّينِ سے صرف یہ مراد نہیں ہے کہ قیامت کو جزا سزا ہوگی بلکہ
68
Page 77
قرآن شریف میں بار بار اور صاف صاف بیان کیا گیا ہے کہ قیامت تو مجازات کبری کا وقت
ہے.مگر ایک قسم کی مجازات اسی دنیا میں شروع ہے جس کی طرف آیت يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا
(الانفال30) اشارہ کرتی ہے.(کشتی نوح.روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 42)
فرمایا کہ میں ملِكِ يَوْمِ الدايين ہوں.جز او سزا دینا اُسی کے اختیار میں ہے.اسی عالم
سے جزاوسزا کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے جو نقب زنی کرتا ہے شاید ایک دفعہ نہیں تو دوسری دفعہ
دوسری دفعہ نہیں تو تیسری دفعہ ضرور پکڑا جاتا ہے یا کسی اور رنگ میں اسے سزا مل جاتی ہے ( یہ
سزا کیا کم ہے کہ چور دولت کے لئے چوری کرتا ہے اور پھر بھی ہمیشہ مفلس اور غریب ذلیل
رہتا ہے ) ہم نے اس عالم میں خوب غور کر کے دیکھ لیا کہ جوسر گرمی سے نیکی کرتا ہے تو نیک
نتیجہ پانے سے خالی نہیں رہتا اور جو بدی کرتا ہے ضرور بد نتیجہ بھگت لیتا ہے دیکھو جو زنا کرتے
ہیں اُن کو آتشک ہو جاتی ہے.شراب پینے والوں کو رعشہ ہو جاتا ہے.کسی کی انتڑیوں میں
پھوڑے نکل آتے ہیں.القصہ خدا کے اس قدر احسان ہیں کہ کس کی طاقت ہے جوان
احسانوں کو شمار کر سکے انسان جس قدر قوی لے کر آیا ہے وہ کس کا عطیہ ہیں.انسان اگر سوچ
کر دیکھے تو سب قویٰ اللہ کی زیر قدرت ہیں چاہے تو ایک دم میں قلب کی حرکت موقوف ہو
جائے اور انسان فور ابلاک ہو جائے مگر مرنے کو کس کا دل چاہتا ہے.البدر نمبر 25 جلد 7 مؤرخہ 25 جون 1908 ، صفحہ 3)
سورہ فاتحہ میں اُس خدا کا نقشہ دکھایا گیا ہے جو قرآن شریف منوانا چاہتا ہے اور جس کو
وہ دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے.چنانچہ اُس کی چار صفات کو ترتیب وار بیان کیا ہے جو
امہات الصفات کہلاتی ہیں جیسے سورہ فاتحہ ام الکتاب ہے ویسے ہی جو صفات اللہ تعالی کی اس
میں بیان کی گئی ہیں وہ بھی اتم الصفات ہی ہیں اور وہ یہ ہیں رَبُّ الْعَلَمِينَ الرَّحْمَنِ
الرَّحِيمِ مُلِكِ يَوْمِ الدِّينِ - ان صفاتِ اربعہ پر غور کرنے سے خدا تعالیٰ کا گویا چہرہ نظر
69
Page 78
آجاتا ہے.الحکم 31 اگست 1901 ، صفحہ 1-2)
واضح ہو کہ ان صفات الہیہ کی ترتیب میں اور بلاغت پائی جاتی ہے جسے ہم
( یہاں ) بیان کرنا چاہتے ہیں.تا صاحب بصیرت لوگوں ( کی بینائی) کے شرمہ سے آپ کی
آنکھیں بھی روشن ہوں اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان صفات کے معابعد جو آیات سجائی ہیں
وہ انہیں صفات پر منقسم ہیں.(یعنی ہر آیت ایک خاص صفت سے متعلق ہے ) بلحاظ ایک
دوسری کے مقابل واقع ہونے کے اور آسمانوں اور زمینوں کے طبقات کی طرح ایک دوسری
کے اوپر تلے رکھے جانے کے.اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ پہلے خدا تعالیٰ نے اپنی ذات اور صفات کا اسی ترتیب کے ساتھ
ذکر کیا جو کائنات عالم میں پائی جاتی ہے.پھر ان تمام امور کو جو بشریت کے مناسب حال ہیں
اسی ترتیب کے ساتھ بیان کیا جو خدائی قانون میں نظر آتی ہے.اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہر
بشری صفت کو ایک الہی صفت کے تحت رکھ دیا.اور ہر انسانی صفت کے لئے ایک صفتِ
الہیہ کو گھاٹ یا پینے کا مقام قرار دیا جس سے وہ مستفیض ہو.خدا تعالیٰ نے ان آیات میں ایک
وضعی ترتیب کے مطابق آپس میں تقابل دکھایا ہے پس بڑا ہی بابرکت ہے اللہ تعالیٰ جو بہترین
ترتیب دینے والا ہے.اس مضمون کی مکمل تشریح یوں ہے کہ یہ صفات ( اللہ تعالی کے ) اسم
ذات سمیت پانچ سمندر ہیں.جن کا ذکر اس سورت کے شروع میں آیا ہے یعنی اللہ، رَبُّ
الْعَلَمِينَ.الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مُلِكِ يَوْمِ الدِّینِ.پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی تعداد کے
مطابق ان (سمندروں) سے مستفیض ہونے والی آیات کا ذکر کیا ہے.اور ان پانچ کو اُن پانچ
کے مقابل پر رکھا ہے.اور ہر فیض حاصل کرنے والی آیت ایک ایسی صفت سے مستفیض ہوتی
ہے جو اس کے مشابہ اور اس کے مقابل ہے.اور اس سے وہ مطالب اخذ کرتی ہے جن پر وہ
صفت حاوی ہے اور جو طالبانِ الہی کو بے حد پسندیدہ ہیں.مثلاً ان میں سے سب سے پہلا
سمندر اللہ (اسم ذات) کا سمندر ہے.اس کے مقابل اِيَّاكَ نَعْبُدُ کا فقرہ ہے جو مقابل میں
70
Page 79
رکھی جانے والی اشیاء کی طرح ہو کر فیض حاصل کرتا ہے.اور عبادت کی حقیقت ہے.پوری
انکساری سے معبود کی تعظیم کرنا اور اس کے نمونہ کو اختیار کرنا.اس کے رنگ سے رنگین ہونا اور
فانی فی اللہ لوگوں کی طرح نفسانیت اور انانیت سے الگ ہو جانا.اس میں راز یہ ہے کہ انسان
کو بیمار اور روگی اور پیاسے کے مثل پیدا کیا گیا ہے.اور اس کی شفاء اس کی پیاس کی تسکین اور
اس کے جگر کی سیر ابی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے پانی سے ہوتی ہے.وہ تبھی صحت مند اور سیراب ہو
سکتا ہے.جب وہ اللہ کی طرف اپنا رُخ موڑ لیتا ہے اور اس کے ساتھ اپنے عشق کو بڑھاتا ہے
اور وہ اس ( معبود حقیقی ) کی طرف پانی کے طالبوں کی طرح دوڑتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کے
سوا کوئی چیز نہ تو اس کی فطرت کو پاک کر سکتی ہے نہ اس کے غبار خاطر کو مجتمع کرسکتی ہے.اور نہ
اس کے منہ کا ذائقہ شیریں بنا سکتی ہے.سنو! اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ان ہی لوگوں کے دل مطمئن
ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے حضور فرمانبردار بن کر آتے ہیں.پس آیت مبارکہ ايَّاكَ نَعْبُدُ میں اللہ تعالیٰ کی معبودیت کا اعتراف ہے جو تمام صفات کا ملہ کا
جامع ہے اور اسی لئے یہ جملہ (ايَّاكَ نَعْبُدُ الْحَمدُ للہ کے جملہ کے تحت ہے.پس تو غور کر !
اگر تو غور کرنے والوں میں سے ہے.ان میں سے دوسرا سمندر رب العالمین کا ہے.اور اس سے إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کا جملہ
مستفیض ہوتا ہے کیونکہ بندہ جب یہ بات سنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کی پرورش کرتا ہے
اور ایسا کوئی عالم نہیں جس کا وہ مرتی نہ ہو اور وہ ( بندہ) اپنے نفس کو بدی کا حکم دینے والا دیکھتا
ہے تو وہ گریہ وزاری کرتا ہے اور مجبور ہو کر اس کے دروازہ کی طرف پناہ ڈھونڈتا ہے.اس کے
دامن سے لپٹ جاتا ہے اور اس کے آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کی (روحانی)
ضیافت گاہ میں داخل ہو جاتا ہے تا وہ (پاک ذات ) اپنی ربوبیت سے اس کی دستگیری
کرے اور اس پر احسان فرمائے اور وہ بہترین احسان کرنے والا ہے.پس ربوبیت
ایک ایسی صفت ہے جو ہر چیز کو اس کے وجود کے مناسب حال خلق عطا کرتی ہے.اور
اس کو ناقص حالت میں نہیں رہنے دیتی.71
Page 80
ان میں سے تیسر ا سمندر الرحمن ہے اور اس سے اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کا
جملہ سیراب ہوتا ہے تا انسان ہدایت اور رحمت پانے والوں میں ہو جائے کیونکہ صفتِ
رحمانیت ہر اُس وجود کو جو صفت ربوبیت سے تربیت پاچکا ہے وہ سب کچھ مہیا کرتی ہے
جس کی اسے حاجت ہو.پس یہ صفت تمام وسائل کو رحم پانے والے کے موافق بنا دیتی ہے
اور ربوبیت کا نتیجہ وجود کو کامل قومی دینا اور ایسے طور پر پیدا کرنا ہے جو اس کے لائق حال
اور مناسب ہے.اسی صفت کا اثر یہ ہے کہ یہ ہر وجود کو اس کے عیوب کو چھپا دینے والا
لباس پہناتی ہے.اسے زینت عطا کرتی ہے.اس کی آنکھوں میں سرمہ لگاتی ہے.اس
کے چہرہ کو دھوتی ہے.اس کو سواری کے لئے گھوڑا دیتی ہے.اور اس کو شاہسواروں
کے طریق بتاتی ہے اور صفت ( رحمانیت) کا درجہ ربوبیت کے بعد ہے وہ ہر چیز کو اس
کے وجود کا مطلوب عطا کر کے اسے توفیق یافتہ لوگوں میں سے بنا دیتی ہے.ان میں سے چوتھا سمندر صفت الرّحِیم ہے اور اس سے صِرَاطَ الَّذِينَ
انْعَمْتَ عَلَيْهِمُ کا جملہ مستفیض ہوتا ہے تا بندہ خاص انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہو
جائے.کیونکہ رحیمیت ایسی صفت ہے جو ان انعامات خاصہ تک پہنچا دیتی ہے جن میں
فرمانبردارلوگوں کا کوئی شریک نہیں ہوتا.گو ( اللہ تعالیٰ کا) عام انعام انسانوں سے لے
کر سانپوں ، اثر د ہاؤں تک کو اپنے احاطہ میں لئے ہوئے ہے.ان میں سے پانچواں سمندر ملِكِ يَوْمِ الدِّينِ ( کی صفت) ہے.اور اس سے
غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ کا جملہ مستفیض ہوتا ہے کیونکہ خدا تعالیٰ کے
غضب اور اس کے (انسان کو ) ضلالت اور گمراہی میں چھوڑ دینے کی حقیقت لوگوں پر مکمل طور
پر جزا اور سزا کے دن ہی ظاہر ہوگی.جس دن اللہ تعالیٰ اپنے غضب اور انعام کے ساتھ جلوہ گر
ہوگا.اور ان کو اپنی طرف سے ذلت دے کر یا عزت دے کر ظاہر کر دے گا.اور اس حد تک
اپنے آپ کو ظاہر کر دے گا کہ اس طرح کبھی اپنے وجود کو ظاہر نہیں کیا ہوگا.اور ( خدا کی راہ
میں ) سبقت لے جانے والے یوں دکھائی دیں گے جیسے میدان میں آگے بڑھا ہوا گھوڑا اور
72
Page 81
گناہگارا پنی کھلی کھلی گمراہی میں نظر آئیں گے.اور اس دن منکروں پر واضح ہو جائے گا کہ وہ
در حقیقت غضب الہی کے مورد تھے اور اندھے تھے اور جو اس دنیا میں اندھا رہے گا وہ آخرت
میں بھی اندھا ہوگا.لیکن اس دنیا کی نابینائی مخفی ہے اور جزا سزا کے دن وہ ظاہر ہو جائے گی.پس جن لوگوں نے انکار کیا اور ہمارے رسول کی ہدایت اور ہماری کتاب ( قرآن کریم) کے
ٹور کی پیروی نہ کی اور اپنے باطل معبودوں کی اتباع کرتے رہے وہ ضرور اللہ تعالیٰ کے غضب
کو دیکھیں گے.اور جہنم کے جوش اور اس کی خوفناک آواز کو سنیں گے.اور اپنی گمراہی اور
کجروی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے.اپنے آپ کو لنگڑے کانے جیسے پائیں گے.اور
جہنم میں داخل ہوں گے.جہاں وہ لمبا عرصہ رہیں گے اور ان کا کوئی شفیع نہیں ہوگا.اس آیت
میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ (خدا کا ) اسم ملِكِ يَوْمِ الدِّينِ دو پہلوؤں والا ہے.وہ جسے چاہے گمراہ ٹھہراتا ہے اور جسے چاہے ہدایت دیتا ہے.پس تم دُعا کرو کہ وہ تمہیں ہدایت یافتہ
بنادے.یہی وہ امر ہے جس کو ہم بیان کرنا چاہتے تھے.یعنی اس آیت کے بعض نکات اور ادبی
لطائف کو جود یکھنے والوں کے لئے روشن نشانوں کی طرح ہیں.اور اس کی حیران کن اچھوتی اور
خوب آراستہ بلاغت کو جو کنایات کی خوبیوں ، حکمت کے موتیوں اور دقائق الہیہ کے نادر
معارف پر حاوی ہے.تم اس بیان کی نظیر نہ تو پہلے لوگوں میں اور نہ بعد میں آنے والے لوگوں
میں دیکھو گے.بلاشبہ اس کی عمدہ ادبی باتیں بے نظیر فضیلت کی حامل ہیں.اس کا قدم علوم کے
پہاڑوں سے بھی اونچا ہے اور وہ عارفوں کے دلوں کو موہ لیتی ہے.اب تو نے ان پانچ سمندروں
کی ترتیب کو معلوم کر لیا ہے.جو ایک دوسرے کے پیچھے جاری ہیں.پس تو انہیں قبول کر اور
شکر گزاروں میں سے ہو جا اور اگر تو فیض اُٹھانے والوں سے بننا چاہے تو فیض اٹھانے والے
جملوں کی ترتیب کو تو ان کے سمندروں کی ترتیب سے پہچان لے گا.کرامات الصادقین روحانی خزائن جلد 7 صفحہ 116-119)
اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ الرَّحْمٰن کے بالمقابل ہے کیونکہ ہدایت پانا کسی کا
73
Page 82
حق تو نہیں ہے بلکہ محض رحمانیت الہی سے یہ فیض حاصل ہو سکتا ہے اور صِرَاطَ الَّذِينَ
أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ الرَّحِيمُ کے بالمقابل ہے کیونکہ اس کا ورد کرنے والا رحیمیت کے
چشمہ سے فیض حاصل کرتا ہے اور اس کے یہ معنے ہیں کہ اے رحم خاص سے دُعاؤں کے قبول
کرنے والے! ان رسولوں اور صدیقوں اور شہیدوں اور صالحوں کی راہ ہم کو دکھا جنہوں نے دُعا
اور مجاہدات میں مصروف ہو کر تجھ سے انواع و اقسام کے معارف اور حقائق اور کشوف اور
الہامات کا انعام پایا اور دائمی دُعا اور تضرع اور اعمالِ صالحہ سے معرفت تامہ کو پہنچے.رحیمیت کے مفہوم میں نقصان کا تدارک کرنا لگا ہوا ہے.حدیث میں آیا ہے کہ اگر فضل
نہ ہوتا تو نجات نہ ہوتی.ایسا ہی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا
نے آپ سے سوال کیا کہ یا حضرت! کیا آپ کا بھی یہی حال ہے؟ آپ نے سر پر ہاتھ رکھا
اور فرمایا ہاں.نادان اور احمق عیسائیوں نے اپنی نافہمی اور نا واقفی کی وجہ سے اعتراض کئے ہیں
لیکن وہ نہیں سمجھتے کہ یہ آپ کی کمال عبودیت کا اظہار تھا جو خدا تعالیٰ کی ربوبیت کو جذب کر رہا
تھا.ہم نے خود تجربہ کر کے دیکھا ہے اور متعدد مرتبہ آزمایا ہے بلکہ ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ جب
انکسار اور تذلیل کی حالت انتہا کو پہنچی ہے اور ہماری روح اس عبودیت اور فروتنی میں پہ نکلتی ہے
اور آستانہ حضرت واہب العطا یا پر پہنچ جاتی ہے تو ایک روشنی اور نور اوپر سے اُترتا ہے اور ایسا
معلوم ہوتا ہے جیسے ایک نالی کے ذریعہ سے مصفا پانی دوسری نالی میں پہنچتا ہے.پس
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت جس قدر بعض مقامات پر فروتنی اور انکساری میں کمال پر
پہنچی ہوئی نظر آتی ہے وہاں معلوم ہوتا ہے کہ اُسی قدر آپ روح القدس کی تائید اور روشنی سے
موئید اور منور ہیں.جیسا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی اور فعلی حالت سے دکھایا
ہے یہاں تک کہ آپ کے انوار و برکات کا دائرہ اسی قدر وسیع ہے کہ ابدالآباد تک اسی کا نمونہ
اور ظل نظر آتا ہے.چنانچہ اس زمانہ میں بھی جو کچھ خدا تعالیٰ کا فیض اور فضل نازل ہو رہا ہے وہ
آپ ہی کی اطاعت اور آپ ہی کے اتباع سے ملتا ہے.میں سچ کہتا ہوں اور اپنے تجربہ سے
کہتا ہوں کہ کوئی شخص حقیقی نیکی کرنے والا اور خدا تعالیٰ کی رضا کو پانے والا نہیں ٹھہر سکتا اور
74
Page 83
ان انعام و برکات اور معارف اور حقائق اور کشوف سے بہرہ ور نہیں ہو سکتا جو اعلیٰ درجہ کے
تزکیہ نفس پر ملتے ہیں جب تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کھویا نہ جائے اور
اس کا ثبوت خود خدا تعالیٰ کے کلام سے ملتا ہے قُل اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي
يُحببكُمُ اللهُ (ال عمران 32) اور خدا تعالیٰ کے اس دعوی کی عملی اور زندہ دلیل میں ہوں اُن
نشانات کے ساتھ جو خدا تعالیٰ کے محبوبوں اور ولیوں کے قرآن شریف میں مقرر ہیں مجھے
شناخت کرو.غرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا کمال یہاں تک ہے کہ اگر کوئی بڑھیا
بھی آپ
کا ہاتھ پکڑتی تھی تو آپ کھڑے ہو جاتے تھے اور اُس کی باتوں کو نہایت توجہ سے سنتے
اور جب تک کہ وہ خود آپ کو نہ چھوڑتی آپ نہ چھوڑتے تھے اور پھر غَيْرِ الْمَغْضُوبِ
عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ مُلِكِ يَوْمِ الدِّينِ کے بالمقابل ہے.اس کا ورد کرنے والا چشمہ
ملِكِ يَوْمِ الدین سے فیض پاتا ہے جس کا مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ اے جزا وسزا کے دن
کے مالک! ہمیں اس سے بچا کہ یہودیوں کی طرح جو دنیا میں طاعون وغیرہ بلاؤں کا نشانہ
ہوئے اور اُس کے غضب سے بلاک ہو گئے یا نصاری کی طرح نجات کی راہ کھو بیٹھیں اس میں
یہود کا نام مغضوب اس لئے رکھا گیا ہے کہ ان کی شامت اعمال سے دنیا میں بھی اُن پر عذاب
آیا کیونکہ انہوں نے خدا تعالیٰ کے پاک نبیوں اور راست بازوں کی تکذیب کی اور بہت سی
تکلیفیں پہنچائیں اور یہ بات بھی یاد رکھنی چاہئے کہ خدا تعالیٰ نے جو یہاں سورہ فاتحہ میں یہودیوں
کی راہ سے بچنے کی ہدایت فرمائی اور اس سورہ کو الضالین پر ختم کیا یعنی ان کی راہ سے بھی
بچنے کی ہدایت فرمائی تو اس میں کیا بسر تھا.اس میں یہی راز تھا کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم
پر بھی ایک قسم کا زمانہ آنے والا ہے جب کہ یہود کی تبع کرنے والے ظاہر پرستی کریں گے اور
استعارات کو حقیقت پر حمل کر کے خدا کے راستباز کی تکذیب کے لئے اٹھیں گے جیسا کہ یہود
نے مسیح ابن مریم کی تکذیب کی تھی اور انہیں یہی مصیبت پیش آئی کہ انہوں نے اس کی تاویل
پر ٹھٹھا کیا اور کہا کہ اگر خدا کا یہی مطلب تھا کہ ایلیا کا مثیل آئے گا تو کیوں خدا نے اپنی
75
Page 84
پیشگوئی میں اس کی صراحت نہ کی.غرض اسی روش اور طریق پر اس وقت ہمارے مخالفوں نے بھی
قدم مارا ہے اور میری تکذیب اور ایذاء دہی میں انہوں نے کوئی دقیقہ باقی نہیں چھوڑا یہاں
تک کہ میرے قتل کے فتوے دیئے اور طرح طرح کے حیلوں اور مکروں سے مجھے ذلیل کرنا اور
نابود کرنا چاہا.اگر خدا تعالیٰ کے فضل سے گورنمنٹ برطانیہ کا اس ملک میں راج نہ ہوتا تو یہ مدت
سے میرے قتل سے دل خوش کر لیتے مگر خدا تعالیٰ نے ان کو ان کی ہر مراد میں نامراد کیا اور وہ جو
اُس کا وعدہ تھا کہ وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ (المائدة 68) وہ پورا ہوا.غرض اس دُعا میں غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ) کا فرقہ مسلمانوں کے ایک گروہ کی اس
حالت کا پتہ دیتا ہے جو وہ مسیح موعود کے مقابل مخالفت اختیار کرے گا اور ایسا ہی الضالين
سے مسیح موعود کے زمانہ کا پتہ لگتا ہے کہ اس وقت صلیبی فتنہ کا زور اپنے انتہائی نقطہ پر پہنچ
جاوے گا اس وقت خدا تعالیٰ کی طرف سے جو سلسلہ قائم کیا جاوے گا وہ مسیح موعود ہی کا سلسلہ
ہوگا اور اسی لئے احادیث میں مسیح موعود کا نام خدا تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت
کا سر الصلیب رکھا ہے کیونکہ یہ سچی بات ہے کہ ہر ایک مجد دفتن موجودہ کی اصلاح کے لئے
آتا ہے اب اس وقت خدا کے لئے سوچو تو کیا معلوم نہ ہوگا کہ صلیبی نجات کی تائید میں قلم اور
زبان سے وہ کام لیا گیا ہے کہ اگر صفحات عالم کو ٹولا جائے تو باطل پرستی کی تائید میں یہ سرگرمی
اور زمانہ میں ثابت نہ ہوگی اور جبکہ صلیبی فتنہ کے حامیوں کی تحریریں اپنے انتہائی نقطہ پر پہنچ
چکی ہیں اور توحید حقیقی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عفت ، عزت اور حقانیت اور کتاب اللہ
کے من جانب اللہ ہونے پر ظلم اور زور کی راہ سے حملے کئے گئے ہیں تو کیا خدا تعالیٰ کی غیرت کا
تقاضا نہیں ہونا چاہئے کہ اس کا سر الصلیب کو اُس وقت نازل کرے؟؟؟ کیا خدا تعالیٰ
اپنے وعدہ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِكرَ وَإِنَّا لَهُ لَحْفِظُونَ (الحجر (10) کو بھول گیا ؟ یقیناً یاد
رکھو کہ خدا کے وعدے سچے ہیں.اس نے اپنے وعدہ کے موافق دنیا میں ایک نذیر بھیجا ہے.دنیا نے اس کو قبول نہ کیا مگر خدا تعالیٰ اس کو ضرور قبول کرے گا اور بڑے زور آور حملوں سے اس
76
Page 85
کی سچائی کو ظاہر کرے گا.میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ میں خدا تعالیٰ کے وعدہ کے موافق
مسیح موعود ہو کر آیا ہوں چاہو تو قبول کرو چاہو تو ر ڈ کرو.( الحكم 10 ستمبر 1901 ، صفحہ 2، الحکم 17 ستمبر 1901 ، صفحہ 1-2)
خلفائے موسیٰ کا سلسلہ ملِكِ يَوْمِ الدّین کے نکتہ پر ختم ہو گیا تھا.چنانچہ اس سلسلہ
کے آخر میں حضرت عیسی آئے اور ظلم و جور کو بغیر کسی لڑائی اور لڑنے والوں کے عدل و احسان
سے بدل دیا گیا.جیسا کہ الدین کے لفظ سے سمجھا جاتا ہے.کیونکہ لغت عرب اور اہلِ عرب
کے سب ادیبوں کے نزدیک یہ لفظ بردباری اور نرمی کے معنوں میں آیا ہے.پس ہمارے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موسی کلیم اللہ سے مماثلت اور خلفائے موسیٰ کی آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم کے خلفاء سے مشابہت نے چاہا کہ اس سلسلہ (محمدی) کے آخر میں بھی کوئی ایسا مرد کامل
پیدا ہو جو حضرت عیسی علیہ السلام کا مثیل ہو اور وہ (لوگوں کو) نرمی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی
طرف بلائے.جنگ کو موقوف کرے، تباہی پھیلانے والی تلوار کو نیام میں کرے اور لوگوں کو
تلوار اور نیزہ کی بجائے خدائے رحمان کے چمکتے ہوئے نشانوں سے ایک نئی زندگی
عطا کرے.پس اس کا زمانہ روز قیامت اور یوم جزا و حشر و نشر سے مشابہت رکھتا ہے.اور وہ
زمین کونُور سے بھر دے گا جیسا کہ وہ اس سے پہلے ظلم اور جھوٹ سے بھری ہوئی تھی.اللہ
تعالیٰ نے یہ مقدر کر رکھا ہے کہ وہ حقیقی یوم الجزاء سے پہلے لوگوں کو اس کا نمونہ دکھائے اور تقویٰ
کے مرجانے کے بعد لوگوں کونئی زندگی بخشے اور یہی مسیح موعود کا زمانہ ہے.اور وہ ( در حقیقت )
اس عاجز کا (ہی) زمانہ ہے.اور اس کی طرف (اللہ تعالی نے ) آیت یوم الدین میں
اشارہ کیا ہے پس تدبر کرنے والے اس بات میں تدبر کریں.اور خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان صفات میں جو فضل و احسان کے مالک اللہ تعالیٰ سے مخصوص
ہیں ان میں خدا تعالٰی محسن حقیقی کی طرف سے ایک حقیقت مخفی ہے اور ایک پیشگوئی پوشیدہ
ہے اور وہ یہ ہے کہ ان صفات کے بیان کرنے سے خدا تعالیٰ کا منشاء یہ تھا کہ اپنے رسول
( مقبول ) کو ان صفات کی حقیقت سے آگاہ کرے اور کئی قسم کی تائیدات کے ذریعہ ان کی
77
Page 86
حقیقت واضح کرے.پس اس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے صحابہ کی ( خاص
رنگ میں ) تربیت فرمائی.اور اس کے ذریعہ ثابت کر دیا کہ وہ رب العلمین ہے.پھر
اپنی صفت رحمانیت کے ذریعہ جو بغیر کسی عامل کے عمل کے ظاہر ہوتی ہے ان پر اپنے انعامات کو
انتہا تک پہنچایا اور اس فیض کے ذریعہ ثابت کر دیا کہ وہ ارحم الرحمین ہے.پھر اس نے اپنی
صفت رحیمیت کے ذریعہ ان کے عمل کے وقت میں انہیں اپنی حمایت کے ہاتھ دکھائے اور
اپنی مہربانی سے روح القدس کے ساتھ ان کی مدد کی.ان کو نفوس مطمئنہ عطا فرمائے اور ان پر
دائمی سکینت نازل کی.پھر اس نے ارادہ کیا کہ انہیں اپنی صفت مالک یوم الدین کا نمونہ بھی
دکھائے تو اُس نے انہیں حکومت اور خلافت بخشی اور ان کے دشمنوں کو ( پہلے ) بلاک ہونے
والوں کے ساتھ ملا دیا.کافروں کو تباہ کردیا اور انہیں پوری طرح ملیا میٹ کر دیا.پھر اس نے
حشر کا نمونہ دکھایا اور ( روحانی لحاظ سے ) قبروں میں پڑے ہوئے لوگوں کو باہر نکالا پس وہ فوج
در فوج اللہ تعالیٰ کے دین میں داخل ہو گئے.اور اس کی طرف فرداً فرداً اور گروہ در گروہ دوڑ
پڑے.پس صحابہ نے مردوں کو زندہ ہوتے دیکھا، اور امساک باراں کے بعد موسلا دھار
بارش دیکھی اور اس زمانہ کا نام یوم الدین رکھا گیا.کیونکہ اس ( زمانہ ) میں حق ظاہر ہو گیا
اور کافروں میں سے فوج در فوج لوگ دین (اسلام) میں داخل ہوئے.پھر اللہ تعالیٰ نے چاہا
کہ امت محمدیہ) کے آخری دور میں بھی ان صفات کا نمونہ دکھائے ، تا بلحاظ کیفیت ملت کا
آخری حصّہ پہلے حصہ کی طرح ہو جائے اور تا گذشتہ اُمتوں کے ساتھ (اس اُمت کی ) مشابہت
پوری ہو جائے.جس کی طرف اس سورت میں اشارہ کیا گیا ہے یعنی ارشاد باری تعالی صراط
الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ میں.پس اس آیت کے الفاظ پر غور کریں.حمد مسیح موعود کے زمانہ کا نام اس لئے بھی یوم الدین رکھا گیا کہ یہ ایسا زمانہ ہے جس میں
دین کو زندہ کیا جائے گا اور لوگوں کو اس امر پر مجتمع کیا جائے گا کہ وہ ( دلی) یقین کے ساتھ
آگے بڑھیں.اور اس میں نہ کوئی شبہ ہے اور نہ ہی (کسی کو) کچھ اختلاف ( ہوسکتا) ہے کہ
78
Page 87
اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس زمانہ کی کئی طریق سے تربیت فرمائی ہے اور رحمانیت اور رحیمیت
کے بہت سے فیوض ہمیں دکھائے ہیں جیسا کہ اس نے پہلے نبیوں، رسولوں، ولیوں اور اپنے
دوستوں کو دکھائے تھے.ان صفات میں سے اب صرف چوتھی صفت باقی رہ گئی.میری مراد
اس سے خدا تعالی کی وہ بجتی ہے جس کا ظہور بادشاہ یا مالک کے لباس میں جزا سزا دینے کے
لئے یوم جزا میں ہوگا.لہذا خدا تعالیٰ نے اس ( تحتی ) کو مسیح موعود کے لئے معجزات کی طرح
قرار دیا اور اُسے ( مسیح موعود کو ) غیبی تائید اور چمکتے نشانوں کے ساتھ حکم اور آسمانی حکومت
کا نمائندہ بنایا.اے مخاطب اتجھے عنقریب اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمُ کی تفسیر کے موقع پر اس حقیقت
کا علم ہو جائے گا اور میں نے یہ باتیں اپنے پاس سے نہیں کہیں بلکہ یہ باریک نکات مجھے اپنے
رب کی طرف سے عطا کئے گئے ہیں.جو شخص ان ( نکات) میں پورا تدبیر کرے گا اور ان آیات میں غور وفکر سے کام لے گا اُسے
معلوم ہو جائے گا کہ ان میں اللہ تعالیٰ نے مسیح موعود اور اس کے زمانہ کے متعلق خبر دی ہے جو
بڑا بابرکت ہے.پھر واضح رہے کہ یہ آیات گویا خدا تعالی خالق کائنات کے لئے حد معرف
کی طرح ہیں.اگر چہ خدا تعالیٰ کی ذات ( در حقیقت ) ہر قسم کی تحدید سے بالا ہے.اس تشریح
سے کلمہ شہادت کے معنے بھی واضح ہو جاتے ہیں جس پر ایمان اور سعادت کا دارومدار ہے.اور
انہی صفات کی بنا پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی) اطاعت کا مستحق ہو گیا ہے.اور عبادت کے
لئے مخصوص ہو گیا کیونکہ وہ ان فیوض کو ارادۂ نازل فرماتا ہے.پس جب تم لا إلهَ إِلَّا اللهُ
کہتے ہو تو عقلمندوں کے نزدیک اس کے یہ معنے ہوتے ہیں کہ دیوی دیوتاؤں میں سے کسی کی
بھی عبادت جائز نہیں عبادت صرف اس ذات کی ہونی چاہئے جو ادراک سے بالا اور ان صفات
کی جامع ہے.اس جگہ میری مراد رحمانیت اور رحیمیت سے ہے جو کہ عبادتوں کے مستحق وجود
کی پہلی شرط ہیں.پھر جان لو کہ اللہ اسم جامد ہے اور اس کی حقیقت کا ادراک نہیں ہوسکتا کیونکہ وہ اسم ذات
79
Page 88
ہے.اور ذات ایسے امور میں سے نہیں جن کا ادراک ہو سکے.لفظ اللہ کو مشتق قرار دے کر جو
معنے کئے جاتے ہیں وہ سب جھوٹ اور محض خرافات ہیں.کیونکہ خدا تعالیٰ کی گنہ (حقیقت) کا
پانا ( تمام خیالات سے بالا اور قیاسات سے دور ہے.جب تم محمد رسول اللہ کہتے ہو تو اس کے
معنے یہ ہیں کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم ) ذات باری کی صفات کے مظہر ہیں.کمالات میں اس کے
جانشین ہیں.اور دائرہ ظلیت کو کامل کرنے والے اور سب رسالتوں کے خاتم ہیں.پس جو کچھ
میں دیکھتا اور پاتا ہوں اس کا ماحصل یہ ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوقات
سے افضل ہیں.وہ اللہ تعالیٰ کی ان ہر دو صفتوں کے وارث ہوئے.پھر جیسا کہ آپ پہلے
رض
معلوم کر چکے ہیں صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جلالی حقیقت کے وارث بنے.اور مشرکوں کا قلع
قمع کرنے میں ان کی تلوار کی دھاک مسلم ہے اور ان کی یاد ایسا امر ہے کہ مخلوق کے پجاری
اسے بھلا نہیں سکتے.انہوں نے صفتِ محمدیت کا پورا پورا حق ادا کر دیا ہے اور انہوں نے
بہتوں کو اپنے جنگی کارناموں کا مزا چکھایا.اب رہی صفت احمدیت جو جمالی رنگوں سے رنگین
ہے اور عشق و محبت کی آگ سے سوختہ ہے.سو مسیح موعود اس صفت ( احمدیت ) کا وارث ہوا
جو ذ رائع ( ترقی ) کے خاتمہ، دشمنوں کی کچلیوں سے ملت کی بربادی اور مددگاروں اور دوستوں
کے معدوم ہونے اور دشمنوں کے غلبہ اور مخالف جماعتوں کے حملہ کے وقت مبعوث کیا گیا تا
اللہ تعالیٰ اندھیری راتوں کے بعد اسلام کی قوت اور (مسلمان) سلاطین کے رعب کے مٹنے
کے بعد اور ملت محمدیہ کے اپاہجوں کی مانند ہو جانے کے بعد اپنی مالکیت یوم الدین کا
نمونہ دکھائے.پس آج ہمارا دین بے وطنوں کی طرح ہو گیا.اس کی حکومت سوائے آسمان
کے اور کہیں باقی نہیں رہی (اس وقت کے ) اہل زمین نے اس کو نہیں پہچانا.اور اسکے خلاف
دشمنوں کی طرح اٹھ کھڑے ہوئے ہیں.پس اس ضعف اور شان وشوکت کے مٹنے کے وقت
( خدا تعالیٰ کے ) بندوں میں سے ایک بندہ مبعوث کیا گیا.تا وہ اس ( روحانی پانی کے)
قحط زدہ زمانہ کو بارش کی طرح سیراب کرے پس یہ وہی مسیح موعود ہے جو اسلام کے ضعف کے
وقت آیا ہے.تا اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل سے لوگوں کو جب کہ وہ چوپایوں کی طرح
80
Page 89
(روحانی) موت مر چکے تھے حشر و نشر اور بعث بعد الموت.قیامت اور جز اسزا کے دن کا
نمونہ دکھائے.پس جان لو کہ یہی زمانہ یوم الدین ہے اور تم یقینا ہماری سچائی کو جان لو گے.اگر چہ کچھ وقت کے بعد ہی سہی.یہاں ایک کشفی نکتہ ہے جو پہلے کبھی نہیں سنا گیا.پس کان لگا کر اطمینان سے سنو اور وہ نکتہ
یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنی ذات کے لئے چار صفات کو محض اس لئے اختیار کیا ہے کہ
تا وہ اس دنیا میں ہی انسان کو ( یعنی دنیا کی ) موت سے پہلے ان صفات کا نمونہ دکھائے.پس
اُس نے اپنے کلام لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأَوْلى وَالْآخِرَةِ (القصص (71) میں اشارہ فرمایا کہ یہ نمونہ
آغا ز اسلام میں بھی عطا کیا جائے گا.اور پھر اُمت کی خواری کے بعد اس کے آخری لوگوں کو بھی
( عطا کیا جائے گا) اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ ( قرآن میں ) فرمایا ہے اور وہ بات
کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ سچاہے ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِنَ الْآخِرِينَ
(الواقعة 40-41) پس اللہ تعالیٰ نے ہدایت، مدد اور نصرت کے زمانہ کو ہمارے نبی کریم صلی
اللہ علیہ وسلم کے زمانہ پر اور اس آخری زمانہ پر جو اس امت کے مسیح کا زمانہ ہے تقسیم
کر دیا.اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَأَخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمُ
(الجمعة (4) اس میں مسیح موعود، اس کی جماعت اور ان کے تابعین کی طرف اشارہ فرمایا ہے.پس قرآن کریم کی نصوص بینہ سے ثابت ہوا کہ یہ صفات ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کے زمانہ میں بھی ظاہر ہوئیں.پھر آخری زمانہ میں بھی ظاہر ہوں گی.اور آخری زمانہ ایسا
زمانہ ہے جس میں بدکاری اور ہر قسم کی خرابیاں بکثرت پھیل جائیں گی اور راستی اور راستبازی
بہت ہی کم ہو جائے گی.اسلام کی ایسی بیخ کنی ہوگی جیسا کہ درخت کو بیخ و بن سے اکھاڑ دیا جاتا
ہے.اور اسلام ایک ایسے شخص کی طرح ہو جائے گاجسے کسی سانپ نے ڈس لیا ہو.مسلمانوں
کی یہ حالت ہو جائے گی کہ گویا کہ وہ مُردے ہیں اور (ان کا) دین خوفناک حوادث اور دوسری
متواتر نازل ہونے والی مصائب کے نیچے کچلا جائے گا اور یہی حال تم اس زمانہ میں دیکھ رہے
ہو.اور تم انواع و اقسام کے فسق، کفر ، شرک اور سرکشی کا مشاہدہ کر رہے ہو اور دیکھ رہے ہو کہ
81
Page 90
کس طرح مفسد زیادہ ہو گئے ہیں اور مصلح اور غم خوار کم ہو گئے ہیں.اور قریب ہے کہ شریعت
نابود ہو جائے اور ملت پوشیدہ ہو جائے.یہ ایسی مصیبت ہے جو نا گہاں وارد ہوئی ہے.ایسی بپتا
ہے جوٹوٹ پڑی ہے.ایسی بدی ہے جو یکدم پھوٹ پڑی ہے اور ایسی آگ ہے جس نے
عرب
و عجم کو جلا دیا ہے.بایں ہمہ ہمارا زمانہ جہاد کا زمانہ نہیں اور نہ تیز تلواروں کا زمانہ ہے.نہ گردنیں مارنے اور زنجیروں میں جکڑنے کا وقت ہے.نہ ہی گمراہوں کو زنجیروں اور طوقوں میں
گھسیٹنے اور اُن پر قتل اور ہلاکت کے احکام جاری کرنے کا زمانہ ہے.یہ زمانہ کافروں کے غلبہ
اور ان کے عروج کا زمانہ ہے اور مسلمانوں پر اُن کے اعمال کی وجہ سے ذلت مسلط کر دی گئی
ہے.اب جہاد بالسیف) کیوں کیا جائے جب کہ (اس زمانہ میں ) نہ کسی کو نماز اور روزہ
سے روکا جاتا ہے نہ حج اور زکوۃ سے اور نہ پاک دامنی اور پرہیز گاری سے اور نہ ہی کسی کافر نے
مسلمانوں کو مرتد کرنے یا انہیں ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لئے ان پر تلوار سونتی ہے.انصاف تو
یہ ہے کہ تلوار کے مقابلہ میں تلوار اٹھائی جائے اور قلموں کے مقابلہ میں قلمیں.ہم آج تلوار اور
نیزے کے زخموں پر نہیں روتے.ہم تو ( ان کی) زبانوں سے پھیلائی ہوئی مفتریات پر روتے
ہیں.(اس زمانہ میں ) انہی مفتریات سے اللہ کے صحیفوں کو جھٹلایا گیا اور ان کے اسرار پر
پر دے ڈالے گئے.ملت (اسلامیہ) کی عمارت پر حملہ کیا گیا اور اس کے گھر کو مسمار کر دیا
گیا.پس یہ (ملت) ایک ایسے شہر کی مانند ہوگئی ہے جس کی فصیلیں ٹوٹ گئی ہوں یا ایسے
باغیچہ کی طرح ہے جس کے درخت جلا دئیے گئے ہوں یا ایسے باغ کی مانند ہے جس کے پھول
اور پھل برباد کر دیئے گئے ہوں اور اس کے شگوفے توڑ کر پھینک دیئے گئے ہوں یا ایسے ملک
کی مانند ہے جو کبھی بہت برکتوں والا تھا لیکن اب اس کی نہریں خشک ہو چکی ہوں یا ایسے
مضبوط محلات کی مانند ہے جن کے نشان تک مٹادئیے گئے ہوں.برباد کر نے والوں نے انہیں
پارہ پارہ کر دیا ہو اور کہہ دیا ہو کہ وہ (ملت) مرچکی ہے اور اس کی موت کی خبر دینے والوں نے اس
کی موت کی خبر دے دی ہو.اس کے حالات چھپ چکے ہوں اور شائع کرنے والوں نے
انہیں شائع کر دیا ہو.بے شک ہر کمال کے لئے زوال ہے اور ہر جوانی نے (ایک
82
Page 91
دن) ڈھلنا ہے.جیسا کہ تمہیں معلوم ہے جب سیلاب کسی مستحکم پہاڑ تک پہنچتا ہے
( و ہیں) رُک جاتا ہے اور رات جب پو پھٹنے کے قریب پہنچتی ہے (اس کی تاریکی
خود بخود ) چھٹ جاتی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ وَالصُّبْحِ إِذَا
تنفّس (التکویر 18-19) پس اللہ تعالیٰ نے رات کے اندھیروں کی انتہا کے بعد صبح کے
ظہور کو ایک لازمی امر قرار دیا ہے.اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے قول يَأَرْضُ ابْلَعِي
(هود 45) سیلاب کے کمال کو سیلاب کے زوال کی علامت قرار دیا ہے.پس اللہ تعالیٰ نے
ارادہ فرمایا کہ وہ مومنوں پر ان کا پہلا زمانہ لوٹا دے اور ان کو دکھائے کہ وہ ان کا رب ہے اور یہ
کہ وہ رحمان اور رحیم ہے اور اس دن کا مالک ہے جب جزا سزا دی جائے گی اور اس میں
مردوں کو ( زندہ کر کے) اٹھایا جائے گا.اس زمانہ میں تم محسن خدا کی ربوبیت اور انسانوں اور
حیوانوں کے لئے اس کی ایسی رحمانیت نمایاں دیکھ رہے ہو جو اجسام سے تعلق رکھتی ہے اور تم
پاتے ہو کہ اس نے کس طرح نئے نئے ذرائع اور مفید وسائل پیدا کئے ہیں.ایسی صنعتیں جن کی
مثال گذشتہ زمانوں میں نہیں دیکھی گئی ایسے عجائبات ( پیدا کئے ہیں ) جن کا نمونہ قرونِ اولیٰ میں
نہیں پایا جاتا اور تمہیں اس زمانہ کی تمام چیزوں میں ایک جدت دکھائی دے رہی ہے جو مسافر
یا قیام پذیر، سکونتی یا پردیسی، تندرست یا بیمار، جنگجو یا معاف کرنے والے صلح جو، قیام یا کوچ کی
حالت اور تمام قسم کی نعمتوں اور مشکلات سے تعلق رکھتی ہے گویا آج دنیا مکمل طور پر بدل دی گئی
ہے.بیشک یہ عظیم ربوبیت اور اعلی رحمانیت ( کا فیض ) ہے اسی طرح تم دینی معاملات میں
بھی ربوبیت، رحمانیت اور رحیمیت ( کے فیوض ) دیکھو گے.یقیناً علوم الہیہ کے طالبوں کے
لئے ہر بات آسان کر دی گئی ہے اور تبلیغ کا کام اور روحانی علوم کی اشاعت کا کام بھی آسان بنا
دیا گیا ہے.اور ہر اس شخص کے لئے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اور اس کی بارگاہ سے
اطمینان ( قلب ) کا متلاشی ہے کھلی کھلی نشانیاں اتاری گئی ہیں.چاند اور سورج کو رمضان کے
مہینہ میں گرہن لگ چکا ہے.اونٹنیاں بیکار کر دی گئی ہیں اور سوائے شاذ و نادر کے ان سے تیز
رفتاری کا کام نہیں لیا جاتا.کچھ عرصہ کے بعد تم مدینہ اور مکہ کے رستہ میں بھی نئی سواری دیکھ لو
83
Page 92
گے اور علماء اور طلباء کے لئے کتابوں کی کثرت اور حصول علم اور معرفت کے بہت سے ذرائع
مہیا کئے گئے ہیں.مسجدیں آباد کی گئی ہیں اور عبادت گذاروں کی حفاظت کی گئی ہے اور امن اور
دعوت وتبلیغ کے دروازے کھل گئے ہیں اور یہ سب رحیمیت ہی کا فیضان ہے.پس ہم پر
واجب ہے کہ ہم گواہی دیں کہ یہ وہ وسائل و ذرائع ہیں جن کی مثال پہلے زمانوں میں نہیں ملتی
اور یہ ایسی توفیق اور آسانی میٹر آگئی ہے جس کی نظیر نہ کبھی کانوں نے سُنی اور نہ ہی اس کا نمونہ
آنکھوں نے کبھی دیکھا پس تم ہمارے رب اعلیٰ کی رحیمیت ( کی شان ) ملاحظہ کرو.یہ اسی کی
رحیمیت ( کی ہی برکت) ہے کہ ہمارے لئے ممکن ہو گیا ہے کہ چند دنوں میں ہی اپنے
مذہب کی اس قدر کتابیں طبع کر دیں جو اس سے قبل ہمارے بزرگ ( کئی ) سالوں میں بھی
نہیں لکھ سکتے تھے.اور اب ہمیں یہ بھی مقدرت ہے کہ ہم دور دور کے ملکوں کی خبریں
( چند ) گھنٹوں میں معلوم کرلیں جن کا حصول ہم سے پہلے لوگوں کے لئے سالہا سال تک اپنی
جانوں کو مشقت میں ڈالنے اور بڑی کوشش کے بغیر ممکن نہیں ہوسکا.یقیناً ہر بھلائی کے
( حاصل کرنے کے لئے ) ہم پر ربوبیت ، رحمانیت اور رحیمیت کے دروازے کھل گئے ہیں
اور اس کے لئے اس قدر زیادہ راستے پیدا ہو گئے ہیں کہ ان کا شمار انسانی طاقت سے باہر ہے.پہلے دعوت وتبلیغ کرنے والوں کو یہ ( آسانیاں ) کہاں میٹر تھیں؟ پس زمین ہماری خاطر خوب
جھنجوڑی گئی ہے اور اس نے اپنے بوجھ ( یعنی خزانے) باہر نکال پھینکے ہیں.نہریں جاری کی
گئی ہیں.دریا خشک کر دیئے گئے ہیں.نئی نئی سواریاں نکل آئی ہیں اور اونٹنیاں بیکار ہوگئی
ہیں.ہمارے پہلوں نے ایسی نعمتیں نہیں دیکھی تھیں جو ہم نے دیکھی ہیں.ہر قدم پر ایک
( نئی ) نعمت ( موجود ) ہے اور یہ نعمتیں ) حد شمار سے باہر ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی دلوں کی
موت اور ان کی سختی بہت بڑھ گئی ہے گویا کہ تمام لوگ مر چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی شناخت
کرنے کی روح ان میں باقی نہیں رہی سوائے بہت کم لوگوں کے جو شاذ و نادر ہونے کی وجہ
سے نہ ہونے کے برابر ہیں پس ان صفات کے ظہور سے جن کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں اور
ربوبیت، رحمانیت اور رحیمیت کی روشن نشانوں کی طرح حجتی سے اور پھر کثرت اموات اور
84
Page 93
.گمراہیوں کے زہر سے لوگوں کے مرنے سے ہم نے جان لیا ہے کہ حشر و نشر کا دن قریب ہے
بلکہ دروازے پر ہے جیسا کہ ان علامات اور اسباب کے ظہور سے واضح ہو گیا ہے کہ کیونکہ
ربوبیت ، رحمانیت اور رحیمیت سمندروں کے جوش مارنے کی طرح موجزن ہیں اور ظاہر
ہوچکی ہیں اور پے در پے نازل ہورہی ہیں اور دریاؤں کی طرح جاری ہیں.لہذا بلاشبہ اب
حشر و نشر کا وقت آگیا ہے.یہ سنت اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ( کے وقت) میں
بھی ہو گزری ہے.پس بلا شبہ یہ زمانہ یوم الدین ہے یوم حشر ہے.آسمانوں کے رب کی
مالکیت اور اس ( مالکیت) کے آثار اہل زمین کے دلوں پر ظاہر ہونے کا دن ہے اور (اس
امر میں بھی) کوئی شک نہیں یہ زمانہ اس مسیح کا زمانہ ہے جو خدائے احکم الحاکمین کی طرف سے
حکم ہے اور لوگوں کی ہلاکت (روحانی) کے بعد ایک حشر کا وقت ہے.اور اس کا نمونہ
حضرت عیسی علیہ السلام کے زمانہ میں بھی اور حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں
بھی گذر چکا ہے.پس تم بھی غور کرو اور غافلوں ( کی صف ) میں شامل نہ ہو.اعجاز المسیح.روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 143-164)
سورہ فاتحہ اس لئے اللہ تعالیٰ نے پیش کی ہے اور اس میں سب سے پہلی صفت رب
العلمین بیان کی ہے جس میں تمام مخلوقات شامل ہے.اسی طرح پر ایک مومن کی ہمدردی کا
میدان سب سے پہلے اتنا وسیع ہونا چاہئے کہ تمام چرند پرند اور کل مخلوق اس میں آ جاوے.پھر
دوسری صفت رحمن کی بیان کی ہے جس سے یہ سبق ملتا ہے کہ تمام جاندار مخلوق سے ہمدردی
خصوصاً کرنی چاہئے اور پھر رحیم میں اپنی نوع سے ہمدردی کا سبق ہے.غرض اس سورہ فاتحہ میں
جو اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہیں یہ گویا خدا تعالیٰ کے اخلاق ہیں جن سے بندہ کو حصہ لینا
چاہئے.اور وہ یہی ہے کہ اگر ایک شخص عمدہ حالت میں ہے تو اس کو اپنی نوع کے ساتھ ہر
قسم کی
ممکن ہمدردی سے پیش آنا چاہئے.اگر دوسراشخص جو اس کا رشتہ دار ہے یا عزیز ہے خواہ کوئی
ہے اس سے بیزاری نہ ظاہر کی جاوے اور اجنبی کی طرح اس سے پیش نہ آئیں بلکہ ان حقوق کی
85
Page 94
پروا کریں جو اس کے تم پر ہیں.اس کو ایک شخص کے ساتھ قرابت ہے اور اس کا کوئی حق ہے
تو اُس کو پورا کرنا چاہئے.الحکم جلد 6 نمبر 30 مؤرخہ 24 /اگست 1902 ، صفحہ 1)
جو شخص عام مسلمانوں میں سے ہماری جماعت میں داخل ہو جائے اُس کا پہلا فرض یہی
ہے کہ جیسا کہ وہ قرآن شریف کی سورۃ فاتحہ میں پنج وقت اپنی نماز میں یہ اقرار کرتا ہے کہ خدا
رب العالمین ہے اور خدا رحمن ہے اور خدا رحیم ہے اور خدا ٹھیک ٹھیک انصاف کرنے والا
ہے.یہی چاروں صفتیں اپنے اندر بھی قائم کرے.ورنہ وہ اس دُعا میں کہ اسی سورۃ میں پنج وقت
اپنی نماز میں کہتا ہے کہ اِيَّاكَ نَعْبُدُ یعنی اے ان چار صفتوں والے اللہ ! میں تیرا ہی پرستار
ہوں اور تو ہی مجھے پسند آیا ہے سراسر جھوٹا ہے.کیونکہ خدا کی ربوبیت یعنی نوع انسان اور نیز
غیر انسان کا مربی بننا اور ادنیٰ سے ادنی جانور کو بھی اپنی مرتبیا نہ سیرت سے بے بہرہ نہ رکھنا یہ
ایک ایسا امر ہے کہ اگر ایک خدا کی عبادت کا دعویٰ کرنے والا خدا کی اس صفت کو محبت کی نظر
سے دیکھتا ہے اور اس کو پسند کرتا ہے یہاں تک کہ کمال محبت سے اس الہی سیرت کا پرستار بن
جاتا ہے تو ضروری ہوتا ہے کہ وہ آپ بھی اس صفت اور سیرت کو اپنے اندر حاصل کرلے تا اپنے
محب کے رنگ میں آ جائے.ایسا ہی خدا کی رحمانیت یعنی بغیر عوض کسی خدمت کے مخلوق پر رحم کرنا یہ بھی ایک ایسا امر ہے
کہ سچا عابد جس کو یہ دعویٰ ہے کہ میں خدا کے نقش قدم پر چلتا ہوں ضرور یہ خلق بھی اپنے اندر پیدا
کرتا ہے.ایسا ہی خدا کی رحیمیت یعنی کسی کے نیک کام میں اس کام کی تکمیل کے لئے مدد کرنا.یہ بھی
ایک ایسا امر ہے کہ سچا عابد جو خدائی صفات کا عاشق ہے اس صفت کو اپنے اندر حاصل
کرتا ہے.ایسا ہی خدا کا انصاف جس نے ہر ایک حکم عدالت کے تقاضا سے دیا ہے نفس کے
جوش سے.یہ بھی ایک ایسی صفت ہے کہ سچا عابد کہ جو تمام الہی صفات اپنے اندر لینا چاہتا ہے
اس صفت کو چھوڑ نہیں سکتا اور راستباز کی خود بھاری نشانی یہی ہے کہ جیسا کہ وہ خدا کے لئے
86
Page 95
ان چار صفتوں کو پسند کرتا ہے ایسا ہی اپنے نفس کے لئے بھی یہی پسند کرے لہذا خدا نے سورۃ
فاتحہ میں یہی تعلیم کی تھی جس کو اس زمانہ کے مسلمان ترک کر بیٹھے ہیں.) تریاق القلوب، روحانی خزائن جلد 15 صفحه 518، 519)
اس سورۃ میں جس کا نام خاتم الکتاب اور اُمّ الکتاب بھی ہے صاف طور پر
بتا دیا ہے کہ انسانی زندگی کا کیا مقصد ہے اور اس کے حصول کی کیا راہ ہے؟
ايَّاكَ نَعْبُدُ گویا انسانی فطرت کا اصل تقاضا اور منشاء ہے اور وہ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کے بغیر پورا
نہیں ہوتا ہے لیکن اِيَّاكَ نَعْبُدُ کو اِيَّاكَ نَسْتَعِينُ پر مقدم کر کے یہ بتایا ہے کہ پہلے ضروری ہے
کہ جہاں تک انسان کی اپنی طاقت، ہمت اور سمجھ میں ہو خدا تعالیٰ کی رضامندی کی راہوں کے
اختیار کرنے میں سعی اور مجاہدہ کرے اور خدا تعالیٰ کی عطا کردہ قوتوں سے پورا کام لے اور اس کے بعد
پھر خدا تعالیٰ سے اس کی تکمیل اور نتیجہ خیز ہونے کے لئے دُعا کرے.( احکم جلد 8 نمبر 36 مورخہ 24 اکتوبر 1904، صفحہ 2.احکم جلد 9 نمبر 11 مؤرخہ 31 مارچ 1905 ، صفحہ 5)
إيَّاكَ نَعْبُدُ میں اگر چہ اِيَّاكَ نَعْبُدُ کو اِيَّاكَ نَسْتَعِينُ پر تقدم ہے لیکن پھر بھی
اگر غور کیا جاوے تو معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی رحمانیت نے سبقت کی ہوئی ہے.ايَّاكَ
نَعْبُدُ بھی کسی قوت نے کہلوایا ہے اور وہ قوت جو پوشیدہ ہی پوشیدہ اِيَّاكَ نَعْبُدُ کا اقرار
کراتی ہے کہاں سے آئی؟ کیا خدا تعالیٰ نے ہی وہ عطا نہیں فرمائی ہے؟ بیشک وہ خدا تعالیٰ
کا ہی عطیہ ہے جو اس نے محض رحمانیت سے عطا فرمائی ہے.اس کی تحریک اور توفیق سے یہ
إيَّاكَ نَعْبُدُ بھی کہتا ہے اس پہلو سے اگر غور کریں تو اس کو تاخر ہے اور دوسرے پہلو سے
اس کو تقدم ہے.یعنی جب یہ قوت اس کو اس بات کی طرف لاتی ہے تو یہ تاخر ہو گیا اور بصورت
اول تقدم.اسی طرح ہر سلسلہ نبوت کی فلاسفی کا خلاصہ یا مفہوم ہے.الحکم جلد 9 نمبر 12 مؤرخہ 10 / اپریل 1905 ، صفحہ 5)
بعض لوگ کہتے ہیں کہ نماز میں لذت نہیں آتی مگر میں بتلاتا ہوں کہ بار بار پڑھے اور
کثرت کے ساتھ پڑھے تقویٰ کے ابتدائی درجہ میں قبض شروع ہو جاتی ہے اس وقت یہ کرنا
87
Page 96
چاہئے کہ خدا کے پاس اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کا تکرار کیا جائے.شیطان کشفی حالت
میں چور یا قزاق دکھایا جاتا ہے اس کا استغاثہ جناب الہی میں کرے کہ یہ قزاق لگا ہوا ہے.تیرے ہی دامن کو پنجہ مارتے ہیں جو اس استغاثہ میں لگ جاتے ہیں اور تھکتے ہی نہیں وہ ایک
قوت اور طاقت پاتے ہیں جس سے شیطان بلاک ہو جاتا ہے.مگر اس قوت کے حصول اور
استغاثہ کے پیش کرنے کے واسطے ایک صدق اور سوز کی ضرورت ہے.اور یہ چور کے تصور
سے پیدا ہو گا جو ساتھ لگا ہوا ہے وہ گویا ننگا کرنا چاہتا ہے اور آدم والا ابتلاء لانا چاہتا ہے.اس
تصور سے روح چلا کر بول اُٹھے گی.اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ.( محکم 17 فروری 1901 ، صفحہ 2)
نمازوں میں اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کا تکرار بہت کرو.اِيَّاكَ نَسْتَعِينُ
خدا کے فضل اور گم شدہ متاع کو واپس لاتا ہے.الحکم 10 نومبر 1902 ، صفحہ 12 )
اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ
اگر نبی کے صرف یہ معنے کئے جائیں کہ اللہ جل شانہ اس سے مکالمہ و مخاطبہ رکھتا
ہے اور بعض اسرار غیب کے اُس پر ظاہر کرتا ہے تو اگر ایک امتی ایسا نبی ہو جائے تو اس میں
حرج کیا ہے خصوصاً جب کہ خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں اکثر جگہ یہ امید دلائی ہے کہ
ایک امتی شرف مکالمہ الہیہ سے مشرف ہو سکتا ہے اور خدا تعالیٰ کو اپنے اولیاء سے مکالمات
اور مخاطبات ہوتے ہیں بلکہ اسی نعمت کے حاصل کرنے کے لئے سورہ فاتحہ میں جو پنج وقت
فریضہ نماز میں پڑھی جاتی ہے یہی دعا سکھلائی گئی ہے اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ
صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمُ تو کسی امتی کو اس نعمت کے حاصل ہونے سے کیوں انکار کیا
جاتا ہے.کیا سورۃ فاتحہ میں وہ نعمت جو خدا تعالیٰ سے مانگی گئی ہے جو نبیوں کو دی گئی تھی وہ درہم و
دینار ہیں.ظاہر ہے کہ انبیاء علیہم السّلام کو مکالمہ اور مخاطبہ الہیہ کی نعمت ملی تھی جس کے ذریعہ
سے اُن کی معرفت حق الیقین کے مرتبہ تک پہنچ گئی تھی اور گفتار کی تجلی دیدار کے قائم مقام ہوگئی
88
Page 97
تھی.پس یہ جودُعا کی جاتی ہے کہ اے خداوند وہ راہ ہمیں دکھا جس سے ہم بھی اُس نعمت کے
وارث ہو جائیں اس کے بجز اس کے اور کیا معنے ہیں کہ ہمیں بھی شرف مکالمہ اور مخاطبہ بخش.بعض جاہل اس جگہ کہتے ہیں کہ اس دُعا کے صرف یہ معنے ہیں کہ ہمارے ایمان قوی کر اور
اعمالِ صالحہ کی توفیق عطا فرما اور وہ کام ہم سے کرا جس سے تو راضی ہو جائے.مگر یہ نادان نہیں
جانتے کہ ایمان کا قومی ہونا یا اعمالِ صالحہ کا بجالانا اور خدا تعالیٰ کی مرضی کے موافق قدم اٹھانا یہ
تمام باتیں معرفت کاملہ کا نتیجہ ہیں.جس دل کو خدا تعالیٰ کی معرفت میں سے کچھ حصہ نہیں ملا وہ
دل ایمان قوی اور اعمالِ صالحہ سے بھی بے نصیب ہے.معرفت سے ہی خدا تعالیٰ کا خوف دل
میں پیدا ہوتا ہے.اور معرفت سے ہی خدا تعالیٰ کی محبت دل میں جوش مارتی ہے.....اب
چونکہ تمام مدار خوف اور محبت کا معرفت پر ہے اس لئے خدا تعالیٰ کی طرف بھی پورے طور پر
اس وقت انسان جُھک سکتا ہے جب کہ اس کی معرفت ہو.اوّل اُس کے وجود کا پتہ لگے اور
پھر اس کی خوبیاں اور اُس کی کامل قدرتیں ظاہر ہوں اور اس قسم کی معرفت کب میٹر آ سکتی ہے
بجز اس کے کہ کسی کو خدا تعالیٰ کا شرف مکالمہ اور مخاطبہ حاصل ہو اور پھر اعلام الہی سے اس بات
پر یقین آ جائے کہ وہ عالم الغیب ہے اور ایسا قادر ہے کہ جو چاہتا ہے کرتا ہے.سو اصلی نعمت
( جس پر قوت ایمان اور اعمال صالحہ موقوف ہیں ) خدا تعالیٰ کا مکالمہ اور مخاطبہ ہے جس کے ذریعہ
سے اول اُس کا پتہ لگتا ہے اور پھر اس کی قدرتوں سے اطلاع ملتی ہے اور پھر اس اطلاع کے موافق
انسان ان قدرتوں کو بچشم خود دیکھ لیتا ہے.یہی وہ نعمت ہے جو انبیاء علیہم السلام کو دی گئی تھی اور
پھر اس اُمت کو حکم ہوا کہ اس نعمت کو تم مجھ سے مانگو کہ میں تمہیں بھی دوں گا.....خدا تعالیٰ کا
مکالمہ اور مخاطبہ یہی تو ایک جڑ ہے معرفت کی اور تمام برکات کا سر چشمہ ہے اگر اس امت پر یہ
دروازہ بند ہوتا تو سعادت کے تمام دروازے بند ہوتے.( براہین احمدیہ حصہ پنجم جلد 21 صفحہ 307 تا309)
یعنی اے ہمارے خدا! ہمیں وہ سیدھی راہ دکھلا جو اُن لوگوں کی راہ ہے جن پر تیر افضل
اور انعام ہوا.اس آیت کے یہ معنے ہیں کہ وہی فضل اور انعام جو تمام نبیوں اور صد یقوں پر
89
Page 98
پہلے ہو چکا ہے وہ ہم پر بھی کر اور کسی فضل سے ہمیں محروم نہ رکھ.یہ آیت اس امت کو اس قدر
عظیم الشان اُمید دلاتی ہے جس میں گذشتہ امتیں شریک نہیں ہیں.کیونکہ تمام انبیاء کے متفرق
کمالات تھے اور متفرق طور پر اُن پر فضل اور انعام ہوا.اب اس امت کو یہ دعا سکھلائی گئی کہ
ان تمام متفرق کمالات کو مجھ سے طلب کرو.پس ظاہر ہے کہ جب متفرق کمالات ایک جگہ جمع
ہو جائیں گے تو وہ مجموعہ متفرق کی نسبت بہت بڑھ جائے گا.اسی بنا پر کہا گیا کہ كُنْتُمْ خَيْرَ
أمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ (آل عمران (111) یعنی تم اپنے کمالات کے رُو سے سب اُمتوں سے
بہتر ہو.(چشمه مسیحی، روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 381،380)
یاد رکھنا چاہئے کہ اس اُمت کے لئے مخاطبات اور مکالمات کا دروازہ کھلا ہے.اور یہ
دروازه گویا قرآن مجید کی سچائی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر ہر وقت تازہ شہادت
ہے اور اس کے لئے خدا تعالیٰ نے سورہ فاتحہ ہی میں یہ دعا سکھاتی ہے اِهْدِنَا الصِّرَاط
الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِم کی راہ کے لئے جو دعا سکھائی تو ان میں
انبیاء علیہم السلام کے کمالات کے حصول کا اشارہ ہے اور یہ ظاہر ہے کہ انبیاء علیہم السلام کو جو
کمال دیا گیا وہ معرفت الہی ہی کا کمال تھا اور یہ نعمت ان کو مکالمات اور مخاطبات سے ملی تھی
اسی کے تم بھی خواہاں رہو.( الحکم24 را کتوبر 1906 صفحہ 4)
سورۃ فاتحہ میں ایک مخفی پیشگوئی موجود ہے اور وہ یہ کہ جس طرح یہودی لوگ حضرت عیسی کو
کافر اور دجال کہہ کر مغضوب علیہم بن گئے بعض مسلمان بھی ایسے ہی بنیں گے.اسی لئے نیک لوگوں
کو یہ دعا سکھلائی گئی کہ وہ منم علیہم میں سے حصہ لیں اور مغضوب علیہم نہ بنیں.سورۃ فاتحہ کا اعلی مقصود
مسیح موعود اور اس کی جماعت اور اسلامی یہودی اور اُن کی جماعت اور ضالین یعنی عیسائیوں کے
زمانہ ترقی کی خبر ہے.سوکس قدر خوشی کی بات ہے کہ وہ باتیں آج پوری ہوئیں.نزول المسیح ، روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 415،414)
90
Page 99
یا درکھو اور خوب یا درکھو کہ سورۃ فاتحہ میں صرف دوفتنوں سے بچنے کے لئے دُعا سکھلائی
گئی ہے.(1) اوّل یہ فتنہ کہ اسلام کے مسیح موعود کو کافر قرار دینا.اُس کی توہین کرنا.اُس کی ذاتیات
میں نقص نکالنے کی کوشش کرنا.اُس کے قتل کا فتویٰ دینا.جیسا کہ آیت غَيْرِ الْمَغْضُوبِ
علیہم میں انہی باتوں کی طرف اشارہ ہے.(2) دوسرے نصاریٰ کے فتنے سے بچنے کے لئے دُعا سکھلائی گئی اور سورۃ کو اسی کے
ذکر پر ختم کر کے اشارہ کیا گیا ہے کہ فتنہ نصاری ایک سیل عظیم کی طرح ہوگا اس سے بڑھ کر
کوئی فتنہ نہیں.غرض اس تحقیق سے ظاہر ہے کہ اس عاجز کی نسبت قرآن شریف نے اپنی پہلی سورۃ میں
ہی گواہی دے دی اور نہ ثابت کرنا چاہئے کہ کن مَغْضُوبِ عَلَيْهِم سے اِس سورۃ میں ڈرایا
گیا ہے؟ کیا یہ سچ نہیں کہ حدیث اور قرآن شریف میں آخری زمانہ کے بعض علماء کو یہود
سے نسبت دی ہے؟ کیا یہ سچ نہیں کہ مَغْضُوبِ عَلَيْهِم سے مراد وہ یہود ہیں جنہوں نے
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو سلسلہ موسویہ کے آخری خلیفہ اور مسیح موعود تھے کا فرٹھہرایا تھا اور
اُن کی سخت تو بین کی تھی اور اُن کے پرائیویٹ امور میں افترائی طور پر نقص ظاہر کئے
تھے.پس جبکہ یہی لفظ مَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ کا ان یہودیوں کے مشیلوں پر بولا گیا جن کا نام
بوجہ تکفیر و توہین حضرت مسیح مَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ رکھا گیا تھا.پس اس جگہ مَغْضُوبِ
عَلَيْهِمْ کے پورے مفہوم کو پیش نظر رکھ کر جب سوچا جائے تو معلوم ہوگا کہ یہ آنے والے
مسیح موعود کی نسبت صاف اور صریح پیشگوئی ہے کہ وہ مسلمانوں کے ہاتھ سے پہلے مسیح کی طرح
ایڈا اٹھائے گا.اور یہ دُعا کہ یا الہی ہمیں مَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ہونے سے بچا.اس کے قطعی،
یقینی یہی معنے ہیں کہ ہمیں اس سے بچا کہ ہم تیرے مسیح موعود کو جو پہلے مسیح کا مثیل ہے ایذا نہ
دیں اُس کو کافر نہ ٹھہرائیں.ان معنوں کے لئے یہ قرینہ کافی ہے کہ مَغْضُوبِ
91
Page 100
عَلَيْهِم صرف ان یہودیوں کا نام ہے جنہوں نے حضرت مسیح کو ایذا دی تھی اور حدیثوں میں
آخری زمانہ کے علماء کا نام یہود رکھا گیا ہے یعنی وہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تکفیر و
توہین کی تھی.اور اس دُعا میں ہے کہ یا الہی ! ہمیں وہ فرقہ مت بنا جن کا نام مَغْضُوبِ
عَلَيْهِمْ ہے.پس دُعا کے رنگ میں یہ ایک پیشگوئی ہے جو دوخبر پر مشتمل ہے.ایک یہ کہ
اس امت میں بھی ایک مسیح موعود پیدا ہوگا.اور دوسری یہ پیشگوئی ہے کہ بعض لوگ اس امت
میں سے اُس کی بھی تکفیر اور توہین کریں گے اور وہ لوگ مورد غضب الہی ہوں گے اور اس
وقت کا نشان یہ ہے کہ فتنہ نصاری بھی اُن دنوں میں حد سے بڑھا ہوا ہوگا.جن کا نام ضالین
ہے اور ضالین پر بھی یعنی عیسائیوں پر بھی اگر چہ خدا تعالی کا غضب ہے کہ وہ خدا کے حکم کے
شنوا نہیں ہوئے مگر اس غضب کے آثار قیامت کو ظاہر ہوں گے.اور اس جگہ مَغْضُوبِ
عَلَيْهِم سے وہ لوگ مراد ہیں جن پر بوجہ تکفیر و توہین و ایذ او ارادہ قتل مسیح موعود کے دنیا میں ہی
غضب الہی نازل ہوگا.یہ میرے جانی دشمنوں کے لئے قرآن کی پیشگوئی ہے.(تحفہ گولڑویہ، روحانی خزائن جلد 17 صفحه 212، 213)
ضالین سے مراد صرف گمراہ نہیں بلکہ وہ عیسائی مراد ہیں جو افراط محبت کی وجہ سے حضرت
عیسی کی شان میں غلو کرتے ہیں.کیونکہ ضلالت کے یہ بھی معنے ہیں کہ افراط محبت سے ایک شخص کو
ایسا اختیار کیا جائے کہ دوسرے کا عزت کے ساتھ نام سُننے کی بھی برداشت نہ رہے جیسا کہ اس
آیت میں بھی یہی معنے مراد ہیں کہ انَّكَ لَفِي ضَلَلِكَ الْقَدِيمِ (يوسف 96).(تحفہ گولڑویہ ، روحانی خزائن جلد 17 صفحه 269 حاشیه در حاشیه )
ضالین پر اس سورۃ کو ختم کیا ہے.یعنی ساتویں آیت پر جو ضالین کے لفظ پر ختم
ہوتی ہے.یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ضالین پر قیامت آئے گی.یہ سورۃ در حقیقت
بڑے دقائق اور حقائق کی جامع ہے جیسا کہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں.اور اس سورۃ کی یہ دعا
که اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ
92
Page 101
عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ یہ صاف اشارہ کر رہی ہے کہ اس امت کے لئے ایک آنے
والے گروہ مَغْضُوبِ عَلَيْهِمُ کے ظہور سے اور دوسرے گروہ ضالین کے غلبہ کے
زمانہ میں ایک سخت ابتلا در پیش ہے جس سے بچنے کے لئے پانچ وقت دعا کرنی چاہئے.اور
یہ دعا سورۃ فاتحہ کی اس طور پر سکھائی گئی کہ پہلے الْحَمْدُ لِلَّهِ سے مُلِكِ يَوْمِ الدِّينِ تک
خدا کے محامد اور صفات جمالیہ اور جلالیہ ظاہر فرمائے گئے تا دل بول اٹھے کہ وہی معبود
ہے.چنانچہ انسانی فطرت نے ان پاک صفات کا دلدادہ ہو کر ایاک نعبد کا اقرار کیا اور پھر
اپنی کمزوری کو دیکھا تو ايَّاكَ نَسْتَعِينُ کہنا پڑا.اور پھر خدا سے مدد پا کر یہ دعا کی جو جمیع اقسام
شر سے بچنے کے لئے اور جمیع اقسام خیر کو جمع کرنے کے لئے کافی و وافی ہے.یعنی یہ دعا کہ
اهْدِنَا القِرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ
عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ.آمين.(تحفہ گولڑویہ.روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 284 285 حاشیہ)
خدا تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ میں ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ وہ دنبال جس سے ڈرایا گیا ہے وہ
آخری زمانہ کے گمراہ پادری ہیں جنہوں نے حضرت عیسی کا طریق چھوڑ دیا ہے.کیونکہ اس نے
سوره ممدوحہ میں یہی دعا سکھلائی ہے کہ ہم خدا سے چاہتے ہیں کہ ایسے یہودی نہ بن جائیں جن پر
حضرت عیسیٰ کی نافرمانی اور عداوت سے غضب نازل ہوا تھا اور نہ ایسے عیسائی بن جائیں جنہوں
نے حضرت عیسیٰ کی تعلیم کو چھوڑ کر اس کو خدا بنا دیا تھا اور ایک ایسا جھوٹ اختیار کیا جو تمام
جھوٹوں سے بڑھ کر ہے اور اس کی تائید میں حد سے زیادہ فریب اور مکر استعمال میں لائے.اس
لئے آسمان پر ان کا نام دخال رکھا گیا اگر کوئی اور دجال ہوتا تو اس آیت میں اس سے پناہ
مانگنی ضروری تھی یعنی سورۃ فاتحہ میں بجائے وَلَا الضَّالین کے ولا الدجال ہونا چاہئے تھا
اور یہی معنی واقعات نے ظاہر کئے ہیں کیونکہ جس آخری فتنہ سے ڈرایا گیا تھا زمانہ نے اسی
فتنہ کو پیش کیا ہے جو تثلیث پر غلو کرنے کا فتنہ ہے.(حقیقۃ الوحی، روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 323 حاشیہ )
93
Page 102
ان لوگوں نے مسیح کو نصف خدائی کا دعویدار بنا دیا ہے.ایسا ہی انہوں نے دجال کی
نسبت مان رکھا ہے کہ وہ مُردوں کو زندہ کرے گا اور یہ کرے گا اور وہ کرے گا.افسوس قرآن تو
ا اله الا اللہ کی تلوار سے تمام اُن باطل معبودوں کو قتل کرتا ہے جن میں خدائی صفات مانی
جائیں پھر یہ دنبال کہاں سے نکل آیا ہے.سورۃ فاتحہ میں یہودی اور عیسائی بننے سے بچنے کی دعا
تو سکھلائی کیا دجال کا ذکر خدا کو یاد نہ رہا جو اتنا بڑا فتنہ تھا؟
الحکم جلد 5 نمبر 3 مؤرخہ 24 /جنوری 1901 ، صفحہ 5)
یہ جوئیں نے ضالین کہا ہے تو اس سے مراد عیسائی اور پادری ہیں.انگریز اس سے
مراد نہیں کیونکہ انگریز تو اکثر ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے ساری عمر میں ایک دفعہ بھی انجیل پڑھی
ہوئی نہیں ہوتی.ان پادریوں پر اسلام ایک بڑا بھاری صدمہ ہے کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ
اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جس کو وہ مغلوب نہیں کر سکتے.یہ جو میں نے ضائین کا ذکر کیا ہے تو اس سے مراد یہی پادری لوگ ہیں جو نہ صرف خود گمراہ
ہیں بلکہ اوروں کو گمراہ کرنے میں بھی پوری ہمت اور کوشش سے کام لیتے ہیں.اور یہ جو
حدیثوں میں دجال کا ذکر آیا ہے تو اس سے مراد ضالین ہی ہیں اور اگر دجال کے معنے
ضالین کے نہ لئے جاویں تو ماننا پڑے گا کہ خدا تعالیٰ نے ضالین کا ذکر تو قرآن شریف
میں کر دیا بلکہ ان کے فتنہ عظیم سے بچنے کے لئے دعا بھی سکھا دی مگر دنبال کا ذکر تک بھی نہ کیا.حالا نکہ وہ ایک ایسا عظیم فتنہ تھا جس سے لکھوکھہا لوگ گمراہ ہو جاتے تھے.غرض سچی بات یہی ہے کہ دجال اور ضالین ایک ہی گروہ کا نام ہے جولوگوں کو گمراہ کرتے
پھرتے ہیں اور اس آخری زمانہ میں اپنے پورے زور پر ہیں اور ہر ایک طرح کے مکر اور فریب
سے خلقت کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے پھرتے ہیں.اور چونکہ دجال کے معنے بھی گمراہ
کرنے والے کے ہیں اسی واسطے احادیث میں یہ لفظ ضالین کی بجائے بولا گیا ہے.اور
احادیث میں ضالین کی بجائے دجال کا لفظ آنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا
94
Page 103
کہ لوگ اپنی طرف سے ایک دنبال بنالیں گے اور عجیب عجیب قسم کے خیالات اس کی طرف
منسوب کریں گے کہ اس کے ایک ہاتھ میں بہشت ہوگا اور ایک ہاتھ میں دوزخ اور وہ خدائی کا
بھی دعوی کرے گا اور نبوت کا بھی.اور اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوا ہوگا اور اس کا ایک گدھا
ہوگا جس کے کانوں میں اس قدر فاصلہ ہوگا اور اس میں یہ یہ باتیں ہوں گی.اس لئے خدا فرماتا
ہے کہ وہ دجالی گروہ ضالین کا ہی ہے جو طرح طرح کے پیرایوں میں لوگوں کو گمراہ کرتے
پھرتے ہیں اور بڑے بڑے وعدے دے دے کر خدا تعالیٰ کی کتابوں میں تحریف تبدیل
کرتے ہیں.اور لوگوں کو خدا تعالیٰ کے حکموں سے بالکل رُوگردان کر رہے ہیں یہاں تک کہ
سور جیسی گندی چیز کو بھی حلال خیال کر رہے ہیں حالانکہ توریت میں سور خاص طور پر حرام کیا
گیا ہے اور خود مسیح نے بھی کہا ہے کہ سوروں کے آگے موتی مت ڈالو.اور ایسا ہی کفارہ جیسا
گندہ مسئلہ ایجاد کر کے انہوں نے گناہوں کے لئے ایک وسیع میدان تیار کر دیا ہے.خواہ
انسان کیسے ہی کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہو مگر یسوع کو خدایا خدا کا بیٹا سمجھنے سے وہ سب عیب
جاتے رہیں گے.اور انسان نجات پا جائے گا اب بتلاؤ کیا یہ صاف سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ وہی
گمراہ کرنے والا گروہ ہے جس کو احادیث میں دجال اور قرآن کریم میں ضالین کر کے پکارا
گیا ہے.الحکم جلد 12 نمبر 3 مؤرخہ 10 جنوری 1908، صفحہ 2)
قرآن نے اپنے اول میں بھی مَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ اور ضالین کا ذکر فرمایا ہے اور
اپنے آخر میں بھی جیسا کہ آیت لَمْ يَلِدُ وَلَمْ يُولَد بصراحت اس پر دلالت کر رہی ہے اور یہ
تمام اہتمام تاکید کے لئے کیا گیا اور نیز اس لئے کہ تا مسیح موعود اور غلبہ نصرانیت کی پیشگوئی
نظری نہ رہے اور آفتاب کی طرح چمک اُٹھے.(تحفہ گولڑویہ، روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 222)
اگر یہ اعتراض ہے کہ اب تو انبیاء کاسلسلہ بند ہوگیا اب کیوں ہمیں
95
Page 104
مَغْضُوبِ عَلَيْهِم بنایا جاتا ہے جب اس امت کے لئے خاتمہ ہے؟
اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ اس قوم میں بھی کئی یہودیوں کا رنگ دکھلائیں
گے.وہ یہودی عیسی کو شولی دینا چاہتے تھے اسی طرح حدیث صحیح میں ہے کہ آخر یہ بھی یہودی
ہوں گے اور خدا کی طرف سے جو آئے گا اس کی تکذیب کریں گے اور اس کے قتل کے
منصوبے کرنا داخل ثواب سمجھیں گے.خدا کی باتیں بے معنی نہیں.یہ عذاب کے دن ہیں
یا نہیں ؟ پچیس برس سے صبر کیا ان لوگوں نے تو اپنی طرف سے کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا.میں نے
ان کے کفر ناموں میں دیکھا کہ لکھتے ہیں اس کا کفر یہود ونصاریٰ کے کفر سے بڑھ کر ہے.تعجب کی بات ہے کہ جو لوگ کلمہ پڑھتے ہیں.قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تعظیم سے لیتے ہیں.جان تک فدا کرنے کو حاضر ہیں.کیا وہ ان
سے بدتر ہیں جو ہر وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے رہتے ہیں.بجز اس کے جو
مسلوب الایمان ہو جائے ایسا الزام نہیں دے سکتا.اگر ان میں ایمان نہیں تو کیا شرافت
بھی جاتی رہی.اللہ تعالیٰ تو خوب جانتا تھا کہ ایسا فرقہ ہونے والا ہے جو مسیح کی تکفیر اپنا ایمان
سمجھے گا.اسی لئے اس دعا میں اس راہ سے بچنے کے لئے دعا سکھلائی.(ماخوذ از تفسیر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام )
حضرت خلیفہ المسیح الاول رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں :
( بدر 9 جنوری 1908 ، صفحہ 7)
شیخ محی الدین ابن عربی لکھتے ہیں کہ میں نے جتنی دفعہ الحمد شریف پڑھا ہے ہر دفعہ
اس کے نئے معنے میری سمجھ میں آئے ہیں.میں اگر چہ ایسا دعویٰ تو نہیں کر سکتا مگر میں نے بغور
دیکھا ہے اور میرا اعتقاد ہے کہ سارا قرآن مجید الحمد شریف کے اندر ہے.الحمد متن ہے
اور قرآن شریف اس کی شرح ہے.96
Page 105
ہید صحابہ کے زمانہ میں ایک شخص کو جو کسی گاؤں کا نمبر دار تھا سانپ نے ڈسا تھا.صحابہ
نے الحمد شریف پڑھ کر اس کا علاج کیا تھا اور اُسے شفا ہو گئی تھی.ایسا ہی ابن قیم نے لکھا
ہے کہ جب میں مکہ معظمہ میں تھا اور طبیب کی تلاش میرے واسطے مشکل تھی تو میں اکثر الحمد کے
ذریعہ اپنی بیماریوں کا علاج کر لیا کرتا تھا.ابن قیم کا میں بہ سبب اُس کے علم کے معتقد ہوں
اور اسے ایسا آدمی جانتا ہوں جو لاکھوں میں ایک ہوتا ہے.میرا اپنا بھی تجربہ ہے کہ میں نے
بہت سے بیماروں پر الحمد کو پڑھا اور انہیں شفا ہوئی.میں چاہتا ہوں کہ لوگ سوچ سوچ کر
الحمد کو نماز میں پڑھا کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں.(ضمیمه اخبار بدر قادیان 4 فروری 1909ء)
کلام الہی کی تین اقسام ہیں.اول بعض نافہم اور ناخواندہ لوگ اس بات سے ناواقف
ہوتے ہیں کہ سر کار و دربار میں کس طرح اور کس مضمون کی درخواست دی جاوے تو اس لئے
کوئی دوسرا شخص جو دربار کے آداب اور قانون سے واقف ہو تو اگر وہ ایسی عرضی لکھ دیوے یاوہ
مضمون بتلاد یوے جس کی دربار میں شنوائی ہو سکے اور اگر چہ مدعا اور آرزو اسی سائل کا اپنا ہو تو
ایسے بتلانے والے اور لکھ دینے والے کو مجرم نہیں قرار دیا جاتا.دنیاوی گورنمنٹ جو کہ آسمانی گورنمنٹ کا ظل ہوتی ہے اس میں ایسے قواعد ہوتے ہیں بعض
فار میں چھپی ہوئی ہوتی ہیں ان پر صرف سائل کے دستخط کرائے جاتے ہیں.اس کی مثال قرآن
شریف میں یہ سورۃ ہے جو بطور عرضی کے ہم کو عطا ہوئی.دوم جولوگ حکام کی پیشی میں بعہدہ سر رشتہ دار وغیرہ ہوتے ہیں وہ کوئی حکم باضابطہ حاکم کی
طرف سے اجازت پا کر لکھ دیا کرتے ہیں وہ بھی اصلی حاکم کا حکم ہی سمجھا جاتا ہے.اس کی مثال
قرآن شریف میں یہ ہے قُل يُعِبَادِيَ الَّذِيْنَ أَسْرَفُوا (الزمر 54)
سوم بعض اوقات خودحاکم اپنے پروانہ جات سے براہ راست حکم سنا دیتا ہے اس کی مثال
سارا قرآن کریم علی العموم ہے.کلام کی ان تین قسموں سے یہ امر بخوبی واضح ہوتا ہے کہ سورۃ فاتحہ میں اور قرآن میں إيَّاك
97
Page 106
نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور دیگر دعاؤں وغیرہ کے الفاظ اس لحاظ سے محلّ اعتراض نہیں
ہو سکتے کہ جس حالت میں قرآن شریف خدائے پاک کا کلام ہے تو اس میں ایسی عبارتیں کیوں
موجود ہیں جو کہ بندوں کی زبانی ہونی چاہیے تھیں.گویا اس طریق سے خدا تعالیٰ نے ایک ادب
اور طریق بارگاہ عالی میں دعا کرنے کا بتلا دیا ہے.البدر 9 جنوری 1903 ، صفحہ 87)
بسْمِ الله جهرا ( نماز میں.مرتب) اور آہستہ پڑھنا ہر دو طرح جائز ہے.ہمارے
حضرت مولوی عبد الکریم صاحب (اللهم اغفرہ وارحمہ) جو شیلی طبیعت رکھتے تھے.رض
بسم اللہ جہڑا پڑھا کرتے تھے.حضرت مرزا صاحب جہر انہ پڑھتے تھے.ایسا ہی میں بھی
آہستہ پڑھتا ہوں.صحابہ میں ہر دو قسم کے گروہ ہیں.میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ کسی طرح
کوئی پڑھے اس پر جھگڑا نہ کرو.ایسا ہی آمین کا معاملہ ہے.ہر دو طرح جائز ہے.بعض جگہ
یہود اور عیسائیوں کو مسلمانوں کا آمین پڑھنابر الگتا تھا تو صحابہ خوب اونچی پڑھتے تھے.مجھے
ہر دو طرح مزہ آتا ہے کوئی اونچا پڑھے یا آہستہ پڑھے.الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
( البدر 23 مئی 1912 ، صفحہ 3)
الحمد للہ.ایسا پاک کلمہ ہے اور اس میں ایسے سمند ر حکمت الہی کے بھرے ہوئے ہیں
کہ جن کا خاتمہ ہی نہیں.میں بعض اوقات نماز میں الحمد للہ پڑھنے کے بعد ٹھہر جاتا ہوں.اس کی وجہ یہی ہے کہ میں ان کے معانی میں غور و خوض کرتا ہوا غرق ہو جاتا ہوں.دیکھو بعض
وقت مجھے بھی سخت سے سخت مشکلات اور تکالیف پہنچتی ہیں کہ ان سے جان جانے کا بھی اندیشہ
ہوا ہے مگر میں نے جب قرآن شریف کو شروع کیا ہے اور اس میں اول ہی اول الْحَمدُ لله
سے شروع ہوا ہے اور میں نے اس آیت پر غور کیا ہے تو دل میں بسا اوقات جوش آیا ہے کہ
بتاؤ تو سہی الحمد للہ کا کیا مقام ہے.ان مصائب اور دکھوں کے سمندر میں کس طرح سے
الحمد لله کہو گے اور ممکن ہے کہ دوسرے مومن کے دل میں بھی آیا ہو کیونکہ میرے دل میں
98
Page 107
ایسا بار ہا آیا ہے تو اس کے واسطے میں نے غور سے دیکھا ہے کہ مصائب اور مشکلات میں واقعی
اللہ تعالیٰ کی ذات سات طرح سے الحمد للہ کہے جانے کے لائق ذات ہے.1.اوّل تو اس لئے کہ مصائب اور شدائد کفارہ گناہ ہوتے ہیں.سو یہ بھی اس کا فضل ہے
ور نہ قیامت میں خدا جانے ان کی سزا کیا ہے.اس دنیا ہی میں بھگت کر نپٹ لیا.2.اس لئے کہ ہر مصیبت سے بڑھ کر مصیبت ممکن ہے.اُس کا فضل ہے کہ اعلیٰ اور سخت
مصیبت سے بچالیا.3.مصائب دو قسم کے ہوتے ہیں دینی اور دنیوی ممکن ہے کہ گناہ کی سزا میں انسان کی
اولا دمرتد ہو جاوے یا یہ خود ہی مرتد ہو جاوے.یہ اس کا فضل ہے کہ اس نے دینی مصائب سے
بچالیا اور دنیوی مشکلات پر اکتفا کر دیا.4.مصائب شدائد پر صبر کرنے والوں کو اجر ملتے ہیں.چنانچہ حدیث شریف میں آیا کہ
ہر مصیبت پر إِنَّا لِلهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھ کر یہ دعا مانگو - اللَّهُمَّ أَجِرْنِي فِي مُصِيبَتِي
وَاخْلُفْنِي خَيْرًا مِنْهَا.اور قرآن شریف میں مشکلات اور مصائب پر صبر کرنے والوں کے
واسطے تین طرح کے اجر کا وعدہ ہے.وبشرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُّصِيبَةٌ
قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ (بقر 156 تا 158 ) یعنی مصائب پر صبر کرنے والوں اور إِنّا
للہ کہنے والوں کو تین طرح کے انعامات ملتے ہیں.5 - صلوات ہوتے ہیں ان پر اللہ کے.6.رحمت ہوتی ہے ان پر اللہ کی.7.اور آخر کا ر ہدایت یافتہ ہو کر ان کا خاتمہ بالخیر ہو جاتا ہے.اب غور کرو جن مصائب کے وقت صبر کرنے والے انسان کو ان انعامات کا تصور آجاوے
جو اس کو اللہ کی طرف سے عطا ہونے کا وعدہ ہے تو بھلا پھر وہ مصیبت ، مصیبت رہ سکتی ہے
اور غم ، غم رہتا ہے؟ ہر گز نہیں.پس کیسا پاک کلمہ ہے الحمد للہ اور کیسی پاک تعلیم ہے وہ
99
Page 108
جومسلمانوں کو سکھائی گئی ہے.یہ نہایت ہی لطیف نکتہ معرفت ہے اور دل کو موہ لینے والی
بات.یہ وجہ ہے کہ قرآن شریف اسی آیت سے شروع ہوا اور رسول
کریم علی کے تمام
خطبات کا ابتدا بھی اس سے ہوا ہے.إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ
( البدر 10 مارچ 1908 ، نیز دیکھیں رسالہ تعلیم الاسلام جلد اول)
بعض لوگ اس مقام پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اوّل مقدم
ہونا چاہئے تھا اور إِيَّاكَ نَعْبُدُ اس کے بعد کیونکہ عبادت کے لئے استعانت اللہ تعالیٰ سے
اوّل طلب کرنی چاہئے.اس کا جواب یہ ہے کہ شرعی امور میں خدا تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ انسان اول خدا تعالیٰ کے
عطا کردہ انعامات سے کام لے کر اس کا شکر یہ ادا کرے تو پھر اللہ تعالیٰ اور انعامات کرتا ہے.چنانچہ یہ امرنبی کریم علیم کی اس حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے جس میں یہ بیان ہے کہ اللہ
تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر میرا بندہ میری طرف ایک بالشت بھر آوے تو میں ایک ہاتھ اس کی
طرف آتا ہوں.اور اگر وہ ہاتھ بھر چل کر آوے تو باع بھر چل کر آتا ہوں اور اگر چل کر آوے تو
میں دوڑ کر آتا ہوں.اس کے علاوہ خود قرآن شریف نے اس مضمون کو لیا جہاں فرماتا ہے اِن
شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ (ابراهيم 8)
پھر ایک اور جگہ فرماتا ہے وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى (محمد 18) خدا تعالیٰ
نے جو قوتیں انسان کو دی ہیں ان سے تو ابھی کام لیا ہی نہیں تو اس کو اور زیادہ مانگنے کی
کیا ضرورت پڑ گئی اور ایسی حالت میں کیوں خدا تعالیٰ اسے اور دیوے.ایسی صورت میں تو اگلا
دیا ہوا بھی واپس لے لینا چاہئے کیونکہ اس سے کام نہیں لیا گیا اور خدا داد نعمت کی قدر نہ کی گئی.تو
ايَّاكَ نَعْبُدُ کے یہ معنے ہیں کہ انسان اعتراف کرتا ہے اور عمل کر کے دکھلاتا ہے کہ اے مولیٰ !
جس قدر تو نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے اس سے تو کام لے رہا ہوں اور موجودہ نعمت کو زوال
100
Page 109
سے محفوظ رکھنے اور اس میں بڑھوتی چاہنے کے لئے تیری ذات پاک سے استعانت طلب
کرتا ہوں.گویا ان آیات کی ترتیب ایک طبعی ترتیب ہے جس کے بدلنے سے لازم آتا ہے کہ
خدا تعالیٰ کا موجودہ قانونِ قدرت ایک احسن اور ابلغ نظام پر نہیں ہے.عبادت کے معنے ہیں عاجزی، انکساری سے فرمانبرداری کرنا.عبادت کے مفہوم میں
اس نکتہ کو ضرور یادرکھنا چاہئے کہ نماز اور روزہ اور دیگر معروفہ عبادات جس ہیئت اور طرز سے
ادا کی جاتی ہیں اس کے خلاف ہیئت اختیار کرنے سے ممکن نہیں کہ ان پر ثواب ملے یا رضائے
الہی کا موجب ہوں.مثلاً یہ روزہ جو کہ ہم رکھتے ہیں اگر ایک خاص وقت تک کھانے پینے سے
باز رہنے کا نام ہے تو ضرور ہے کہ ہم جمعہ کو یا عید کے دن بھی روزہ رکھ لیا کریں تو ثواب ملے.لیکن ان ایام میں روزہ رکھنے سے تو ثواب کی بجائے عذاب ہوتا ہے.اس سے معلوم ہوتا ہے
که مطلق روزہ اپنی ذات سے عبادت نہیں ہے.اسی طرح اگر نماز بہ ایں بیت کہ ہم
ادا کرتے ہیں اگر عبادت ہے تو فجر کی دورکعت کی بجائے اگر تین یا چار پڑھ لیں تو بھی ثواب
ہونا چاہئے بلکہ زیادہ ہونا چاہئے کیونکہ محنت زیادہ ہوئی.وہی کلمات ہیں جن کی تکرار کثرت سے
کی گئی ہے.مگر ظاہر ہے کہ دو کے بجائے چار تو در کنار صرف ایک رکن نماز ہی بڑھا دینے
سے نماز باطل ہو کر موجب عذاب ہو جاتی ہے.تو معلوم ہوا کہ نما ز مطلق اپنی ذات سے عبادت
نہیں ہے.پھر ہم معاشرت کو دیکھتے ہیں کہ وہی چہل پہل اور محبت اور پیار اور راز و نیاز کی
باتیں اور معاشرت کی حرکات ہیں کہ جب انسان اپنی منکوحہ بیوی سے معاشرہ کرتا ہے تو ثواب
پاتا ہے.لیکن جب ایک نامحرم عورت سے کرتا ہے تو عذاب کا مستحق ہے.حالانکہ عورت
ہونے میں تو بیوی اور نامحرم ایک ہی ہیں اور وہی حرکات ہیں.تو ان نظائر سے معلوم ہوتا ہے کہ
نماز روزہ معاشرت اور دیگر عبادات شرعیہ مطلق اپنی ذات اور ہیئت کے لحاظ سے ہر گز نہیں
ہیں.بلکہ اس لئے عبادت کا لفظ ان پر آتا ہے کہ یہ خدا تعالیٰ کے حکم سے کی جاتی ہیں.اور جب
ان میں ایک ذراسی بات بھی اپنی طرف سے ملا دی جاوے تو پھر یہ عبادت نہیں رہتیں اور اس
101
Page 110
سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ عبادت کے معنے اصل میں اطاعت کے ہی ہیں اور ہر قابل اطاعت
چونکہ تعظیم کا مستحق ہوتا ہے اس لئے اس کے معنے عظمت اور عزت کے بھی ہیں.إيَّاكَ نَسْتَعِينُ کا کلمہ خالص توحید کی طرف راہ نمائی کرتا ہے کہ خدا تک پہنچنے کے
واسطےصرف خدا کو ہی ذریعہ بنایا جاوے اور اس کلمہ کا قائل یہ اقرار کرتا ہے کہ وہ خداشناسی
کا مرحلہ طے کرنے کے واسطے کسی اور شے کو ذریعہ نہیں بناتا.نہ کسی بت کو.یہ مخلوق کو.نہ
عقل کو.نہ علم کو.اور اپنی ہر ایک احتیاج کے واسطے وہ خدا ہی کی طرف رجوع کرتا ہے.( البدر 16 جنوری 1903 ، صفحہ 95)
نماز میں ہر روز محبوب حقیقی جامع جمیع کمالات، رحمن رحیم ، حضرت رب العالمین، مالک
یوم الدین کی تعریف کر کے آپ پڑھا کرتے ہو.إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا
القِرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ اِيَّاكَ نَعْبُدُ کے معنی ہیں تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کریں
گے.یہ دعویٰ سب مسلمان رات دن کئی بار خداوند عالم سے کرتے ہیں.پیارے دیکھ اس دعویٰ
میں ہم کس قدر سچے ہیں ؟ رات کو سور ہے.چار پہر تین پہر سوتے رہے.صبح کو اٹھے پاخانے
گئے.وہاں سے آئے باتیں کیں.پھر کھانے کی فکر میں لگے.روٹی کھائی.پھر کچہری میں دنیا
کمانے کو گئے.پھر جو جو کام وہاں کرتے ہیں اس کو ہم ہی خوب جانتے ہیں.پھر آئے.ہوا خوری - کوچه گردی.سیر بازار.گھر آئے.بال بچہ میں لگ گئے.لیاقت و
استعداد پر الف لیلہ.فسانہ آزاد.کفارسیان وغیرہ وغیرہ پڑھنے بیٹھ گئے.بتاؤ یہی ايَّاكَ نَعْبُدُ
کا مطلب ہے؟ پھر اگر کوئی بہت بڑا نیک ہوا تو پنجگانہ نماز بھی درمیان میں پڑھ لی.پھر اس
میں ریا، شمعة ، سستی ، کاہلی ، تاخیر وقت ، نقصان سجود، رکوع، قومہ،جلسہ وقراءت ہوتا ہے.جو
منصف ہے اسے خوب جانتا ہے.بھلا پیارے یہ معنی اِيَّاكَ نَعْبُدُ کے ہوں گے؟ نہیں نہیں.بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو ہر ایک کام میں اور بات میں رضامندی جناب باری تعالیٰ کی
مد نظر رکھنی چاہئے.نوکری کریں مگر اس نیت پر کہ روپیہ حاصل کر کے صلہ رحمی کریں گے.ماں
کو ، بہن کو بھائی ، بھانجا بھتیجا وغیرہ کو دیں گے.صلہ رحمی سے رب تعالیٰ راضی ہوگا.جہاں
102
Page 111
تک ہوسکا لوگوں کی بہتری میں کوشش کریں گے.سوتے ہیں مگر اس نیت سے کہ خواب
سے طاقت کمانے کی حاصل ہوگی.بدن کو صحت میں عبادت پر لگائیں گے.وہ روزی جس
سے صلہ رحمی ہو اور آپ سوال، چوری، فریب ، قمار وغیرہ وغیرہ سے آدمی بچے.کمانے کی طاقت
اُسے نیند سے حاصل ہوتی ہے اس واسطے سوتے ہیں.لوگوں سے باتیں کرتے ہیں اس خیال
سے کہ باہم محبت بڑھے، اتفاق پیدا ہو.جو خداوند کریم کا حکم ہے اسی طرح ہر ایک کام میں
رضامندی مولی مقصود ہو اور وہی مد نظر رہے تو ايَّاكَ نَعْبُدُ کے معنے صحیح ہم پر صادق آویں اور
دعویٰ درست ہو.اب چلو إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ! اس کے معنی ہیں تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں.یہ بھی دعوی ہے.سچا تب ہو جب ہر کام میں ہم کو یہی خیال رہے کہ اس کا انجام اور اتمام پڑوں رضا مندی
حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ اور اس کی عنایت کے نہیں ہوسکتا.اے خدا تو ہی ممد اور معاون رہ.دیکھو کبھی زمیندار کاشتکاری کرتا ہے.خرمن بناتا ہے.امیدوار ہے کہ دانہ گھر کو لے جاویں.خرمن کو آگ لگ جاتی ہے اور گناہ کی شامت وہ خرمن خاکستر کا انبار ہو جاتا ہے.اسی کارحم ہو
کہ معاصی عفو ہو جاویں اور اس خرمن سے ہم نفع اٹھاویں.پس ضرور ہوا کہ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ
میں ذاتِ باری پر اعتما در ہے.(احکم 28 فروری 1902 ، صفحہ 2)
حمد واؤ حالیہ ہے ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور اس حال میں کہ تجھ سے مدد چاہتے ہیں
کیونکہ تیرے فضل کے سوائے عبادت کی توفیق بھی حاصل نہیں ہو سکتی.اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ
ضمیمه اخبار بدر قادیان 4 فروری 1909ء)
اهْدِنَا الصِّراط سے یہ مطلب ہے کہ الہی کوئی کام ہڈوں سبب واقعی نہیں ہوا کرتا
اور ہم کو کاموں کے اسباب ٹھیک معلوم نہیں اس لئے ہمارے کام نہیں ہوتے.اگر بیماری کی
صحت کا ٹھیک سبب معلوم ہو تو ہمارے بیمار کیوں بیمار ر ہیں؟ اور اگر دفع افلاس کے واقعی
103
Page 112
اسباب معلوم ہوں تو ہم کیوں مفلس رہیں ؟ عزت کے اسباب دریافت ہو جاویں تو جلد تر
ذی عزت ہور ہیں.ذلت کے اسباب معلوم ہوں تو ان سے بچیں اور ذلیل نہ ہوں.پادشاہ ہو
جانے کے اسباب دریافت ہوں تو پادشاہ بنیں.غرض ہر وقت ہر آن میں ہم کو ضرور ہے کہ
خداوند کریم کی درگاہ میں سوال کرتے رہیں کہ الہی فلاں کام میں سبب حقیقی کی راہنمائی
فرما.فلاں میں راہنمائی عطا کر.اگر ہر وقت کاموں کی ضرورت ہو تو ہر وقت اهْدِنَا الصِّراط
الْمُسْتَقیم کی ضرورت بھی لگی ہوئی ہے.پھر صبح نماز کے بعد کئی بار اسی طرح اهْدِنَا
القِرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کیا ساری الحمد فکروں کے ساتھ پڑھنی چاہئے.الحكم 28 فروری 1902 صفحه (2)
صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا
الضالين
أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ جن پر تیرا انعام ہوا.منعم علیہ کی تفسیر خود قرآن نے کردی ہے.مِنَ النَّبِينَ وَالصَّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّلِحِينَ (النساء 70)
انسانی افعال کے چار ہی مراتب ہوا کرتے ہیں.اول مطلق کام صلاحیت سے کرنا.اسے
صالح کہتے ہیں.دوسرے جب آقایا حاکم سر پر کھڑا ہو تو وہ اس کام کو اور بھی تیزی سے کرتے
ہیں تو اسے شہید کہتے ہیں.تیسرے ٹھیکہ کے طور پر کام کرنا جس میں انسان کو خود بخود ہی ایک فکر
لگی ہوتی ہے کہ اس میں کوئی نقص نہ رہے اور بڑی دیانت سے کام لیتا ہے.اسے صدیق کہتے
ہیں.چوتھے ایک کام میں اپنے آپ کو ایسا محوکرنا کہ وہ طبعی تقاضا ہو جاوے اور جیسے ایک مشین
انجن کے زور سے خود بخود کام کرتی ہے.بھکتی ہے، نہ ست ہوتی ہے، اسی طرح افعالِ حسنہ
کا اس سے سرزد ہونا.اسے نبی کہتے ہیں.البد 16 فروری 1909ء)
مَغْضُوبِ : یہود جن میں بے جا عداوت ہے اور علم پڑھ کر عمل نہیں کرتے.ضالین: بہکے ہوئے نصاری.انہوں نے اپنے نبی سے بے جا محبت کی اور علوم الہی کو
104
Page 113
سیکھنے کی بجائے اپنی رائے کے تابع ہوئے.الضَّالّين: راستہ سے بہک جانے والے.بے جا محبت کرنے والے بے علم.حضرت مسیح موعود نے اس کے معنے گم ہو جانے والے کے کئے ہیں کیونکہ یہ لوگ آخر اسی سلسلہ
میں گم ہو جائیں گے.اور اس مضمون پر دلیل یہ آیت قرآنی ہے ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ
(سجده آیت 11)
البدر 16 جنوری 1903ء)
ضالین: ان کے دونشان ہیں.1.الہیات کا علم نہ ہو.مَالَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا
لاباءهم (كهف 6)
2 کسی سے بے جا محبت.جیسے نصاری.مضالین میں چونکہ شنڈ و مڈ ہے اس میں بتایا کہ ان
کا زمانہ لمبا اور مضبوط ہوگا.( تشحیذ الا ذبان ماہ ستمبر 1913ء)
ہم نے تین دعائیں الحمد میں کی ہیں.منظم علیہ بنیں.مغضوب
علیھم اور صال نہ
بنیں.ہر سہ خدا نے قبول کی ہیں.انعام ان پر ہوا جو متقی ہیں.مغضوب بے ایمان منکر ہیں جن
کو وعظ کرنانہ کرنا برا بر ہو.ضالین منافق لوگ ہیں.ہر سہ کا ذکر الحمد میں ہے.پھر ترتیب
وار ہر سہ کا ذکر سُورۃ بقرہ کے ابتدا میں ہے.یہ قرآن شریف کی ترتیب کا ایک نمونہ ہے.(ماخوذ از حقائق الفرقان )
حضرت خلیفہ المسیح الثانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:
سورۃ کے معنی عربی زبان میں مندرجہ ذیل ہیں.( بدر 23 رمئی 1912 ، صفحہ 3)
(1) مَنْزِلَةٌ یعنی درجہ (2) شَرَف یعنی بزرگی بڑائی (3) عَلامَةٌ یعنی نشان (4)
اونچی دیوار یا عمارت جو خوبصورت بھی ہو.( اقرب)
(5) یہ لفظ سُورۃ سے بھی ہو سکتا ہے یعنی اس میں ہمزہ ہے جو ما قبل مضموم کی وجہ سے واؤ
105
Page 114
سے بدل گیا ہے.اس لفظ کے معنی بقیہ کے ہیں.عرب کہتے ہیں هُوَ في أشار الناس یعنی وہ
قوم کے بقیہ لوگوں میں سے ہے ( الجامع لاحکام القرآن للقرطبی)
(6) ایسی شے جو پوری اور مکمل ہو.عرب جوان تندرست اونٹنی کو سورۃ کہتے ہیں.سُورَة
کی جمع سور ہے یعنی سورتیں.قرآن کریم کے بعض ٹکڑوں کو سُورۃ کیوں کہتے ہیں؟ اس کے متعلق مختلف علماء
نے مختلف توجیہات بیان کی ہیں.بعض کے نزدیک اس لئے کہ ان کے پڑھنے سے انسان کا
درجہ بڑھتا ہے.بعض کے نزدیک اس لئے کہ اس سے بزرگی حاصل ہوتی ہے.بعض کے
نزدیک اس لئے کہ سورتیں مضامین کے ختم ہونے کا نشان ہیں.بعض کے نزدیک اس لئے
کہ وہ ایک بلند اور خوبصورت روحانی عمارت کو دنیا کے سامنے پیش کرتی ہیں.بعض کے
نزدیک اس لئے کہ وہ سارے قرآن کا بقیہ یا حصہ ہیں.بعض کے نزدیک اس لئے کہ ان
کے اندر ایک مکمل اور پورا مضمون آ جاتا ہے.یہ امر ظاہر ہے کہ یہ اختلاف صرف ذوقی ہے
ور نہ سورۃ کے چھ معنی جو بیان ہوئے ہیں وہ چھ کے چھ ہی اس جگہ چسپاں ہوتے ہیں اور ہم کہہ
سکتے ہیں کہ قرآن کریم کے معین ٹکڑوں کو سورۃ اس لئے کہا جاتا ہے کہ وہ (1) قرآن کریم کا
حصہ ہیں (2) اور ان میں سے ہر اک میں ایک مکمل اور پورا مضمون بیان ہوا ہے(3) وہ بلند
اور خوبصورت روحانی تعمیر پر مشتمل ہیں جن میں داخل ہونے والا (4) اعلیٰ مرتبہ اور (5) بزرگی
پاتا ہے اور (6) ان پر عمل کرنے والے کو دوسرے لوگوں کے مقابل پر ایک خاص امتیاز
حاصل ہو جاتا ہے.سورۃ کا لفظ خود قرآن کریم نے استعمال فرمایا ہے اور الہامی نام ہے.رسول کریم صلی اللہ
علیہ وسلم بھی یہ لفظ استعمال فرماتے تھے.سُوْرَةُ الفَاتِحَه
قرآن کریم کے ابتدا میں رکھی ہوئی اس مختصر سی سورۃ کا نام فاتحۃ الکتاب ہے جو مختصر ہو کر سورۃ
الفاتحہ بن گیا ہے.اردو دان لوگوں نے آگے اسے فارسی اسلوب پر سورۃ فاتحہ بنا دیا ہے.اس
106
Page 115
کا یہ نام ترمذی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مروی ہے.اس سورۃ کے کئی نام ہیں جن میں سے مشہور نام جو بعض قرآن کریم سے اور بعض رسول کریم
صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں ذیل میں درج کئے جاتے ہیں.سُورةُ الصَّلوة
حضرت ابوہریرہؓ فرماتے ہیں.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا.اللہ تعالیٰ فرماتا
ہے قَسَمْتُ الصَّلوةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِى نِصْفَينِ (مسلم باب و جوب قراءة
الفاتحه في كل ركعة) میں نے صلوۃ ( یعنی سورۃ فاتحہ ) کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان
نصف نصف کر کے تقسیم کر لیا ہے یعنی آدھی سورۃ میں صفات الہیہ کا ذکر ہے اور آدھی میں بندے
کے حق میں دُعا ہے.سورة الحمد
ابو داؤد میں حضرت ابوہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ
الحمد للہ کے دوسرے نام ام القرآن اور ام الکتاب اور السبع المثانی بھی ہیں.( ابوداؤد کتاب
الصلوۃ باب فاتحۃ الکتاب)
(3,4,5) اُمُّ الْقُرْآنِ الْقُرْآنُ الْعَظِيم اور السَّبُعُ الْمَعَانِي یہ تین نام بھی اس سورۃ
کے ہیں.مسند امام احمد بن حنبل میں ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
رض
فرمایا سورۃ فاتحہ ائم القرآن بھی ہے اور السبع المثانی بھی ہے اور القرآن العظیم بھی ہے.السبع المثانی کا لفظ قرآن کریم میں بھی استعمال ہوا ہے ( الحجر ع 6) پس یہ نام قرآن کریم کا
رکھا ہوا ہے.ہے.(6) ام الکتاب.اس نام کا ذکر ابوداؤد میں حضرت ابوہریرۃ کی روایت میں موجود
107
Page 116
(7) الشفاء - یہ نام حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے.فرماتے ہیں.رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ فاتحہ ہر بیماری سے شفادیتی ہے.(8) الرقیه.یعنی دم کرنے والی سورۃ.یہ نام بھی حضرت ابوسعید خدری کی روایت مذکورہ
مسند احمد بن حنبل و بخاری میں درج ہے.ایک شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا
کہ کسی کو سانپ نے ڈس لیا تھا میں نے اس پر سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کیا تھا اور اسے شفا ہوگئی اس
پر آپ نے فرمایا.مَا يُدْرِيكَ أَنَّهَارُقْيَةٌ تم کو کس طرح معلوم ہوا کہ یہ دم کرنے والی سورۃ
ہے.اس صحابی نے جواب دیا.یا رسول اللہ بس میرے دل میں ہی یہ بات آ گئی.(9) سُورَةُ الكنز - حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے جو احسان فرما کر مجھے انعام دیتے ہیں ان میں سے ایک فاتحۃ الکتاب
بھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا کہ یہ میرے عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ
ہے.ان کے علاوہ اور نام بھی اس سورۃ کے صحابہ سے مروی ہیں.امام سیوطی نے ان کی تعداد
پچیس تک
لکھی ہے.فاتحہ نام جو اس سورۃ کا بیان ہوا ہے اس کو یہ خصوصیت بھی حاصل ہے کہ یہ نام پیشگوئی
کے طور پر پہلی کتب میں بھی آیا ہے.چنانچہ مکاشفات باب 10 آیت 2 میں لکھا ہے.اور اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی کتاب کھلی ہوتی تھی اور اس نے اپنا داہناں پاؤں
سمندر پر اور بایاں خشکی پر دھرا اور بڑی آواز سے جیسے ببر گرجتا ہے پکارا.اور جب اس نے
پکا را تب بادل نے گرجنے کی اپنی سات آواز میں دیں.“
مترجم نے پیشگوئی کی اصل حقیقت سے نا آشنا ہونے کے باعث عبرانی لفظ ” فتوحہ کا
ترجمہ کھلی ہوئی کتاب کیا ہے حالانکہ فتوحہ یعنی فاتحہ سورۃ کا نام بتایا گیا تھا.حمد ان ناموں سے سورۃ فاتحہ کے وسیع مطالب پر روشنی پڑتی ہے یہ 9 نام در حقیقت دس
مضمون ہیں جو سورۃ فاتحہ بیان کرتی ہے.وہ فاتحۃ الکتاب ہے.یعنی قرآن کریم میں سب
سے پہلے اس کے رکھنے کا حکم ہے دوسرے وہ مطالب قرآنی کے لیے بمنزلہ ایک کلید کے ہے
108
Page 117
کہ اس کے ذریعہ سے قرآن کریم کے مطالب کھلتے ہیں.پھر سورۃ فاتحہ سورۃ الحمد ہے
یعنی اس سورۃ نے انسان اور بندہ کے تعلقات پر اور انسانی پیدائش پر اس رنگ میں روشنی ڈالی
ہے کہ اس سے صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ انسانی پیدائش اعلی ترقیات کے لئے ہے اور یہ کہ خدا
تعالی کا تعلق بندوں سے رحم اور فضل کی بنیادوں پر قائم ہے.پھر وہ الصلوۃ ہے یعنی کامل دعا
اس میں سکھائی گئی ہے جس کی مثال اور کہیں نہیں ملتی.اور وہ اُٹھم الکتاب ہے اس میں وہ
تمام علوم جن کے ذریعہ سے دوسروں کو خطاب کیا جاتا ہے بیان کر دئے گئے ہیں اور یہ بھی کہ
وہ کتاب کریم یعنی قرآن مجید کے لئے بمنزلہ ماں کے ہے یعنی قرآن کریم کے نزول کا موجب
وہ دعائیں ہیں جو سورۃ فاتحہ میں بیان ہوئی ہیں اور جو دردمند دلوں سے اٹھ کر عرش عظیم سے قرآن
کریم کو لائی ہیں اور وہ اُٹھ القرآن ہے اس میں وہ تمام علوم جو انسان کی ذات سے تعلق رکھتے
ہیں بیان کر دیئے گئے ہیں.اور وہ اسبع المثانی ہے یعنی گو صرف سات آیتیں اس میں ہیں لیکن
ہر ضرورت ان سے پوری ہو جاتی ہے.روحانیت کا کوئی سوال ہو کسی نہ کسی آیت سے اس پر
روشنی پائی جائے گی.گویا علمی سوالوں کے حل کرتے وقت بار بار حوالہ کے طور پر اس کی سات آیتیں
دہرائی جائیں گی اور اس لئے بھی وہ مثانی ہے کہ نماز کی ہر رکعت میں اسے پڑھا جاتا ہے.وہ قرآن عظیم بھی ہے یعنی با وجود ام الکتاب اور اُم القرآن کہلانے کے وہ قرآن کریم
کا حصہ بھی ہے اور اس سے الگ نہیں جیسا کہ بعض لوگوں نے غلطی سے سمجھ لیا ہے.قرآن عظیم
سورۃ فاتحہ کو انہی معنوں سے کہا گیا ہے جس طرح ہم کسی سے کہتے ہیں قرآن سناؤ اور مراد اس
سے ایک سورۃ ایک رکوع ہوتا ہے.ما سورۃ فاتحہ شفا ہے کہ اس میں تمام ان وساوس کا رد ہے جو انسان کے دل میں دین
کے بارہ میں پیدا ہوتے ہیں اور وہ رُقيّة ہے کہ علاوہ دم کے طور پر استعمال ہونے کے اس کی
تلاوت شیطان اور اس کی ذریت کے حملوں سے انسان کو بچاتی ہے اور دل میں ایسی قوت پیدا
کرتی ہے کہ شیطان کے حملے بے ضرر ہو جاتے ہیں اور وہ کنز بھی ہے کہ علوم وفنون کے اس
میں دریا بہتے ہیں.اردو میں دریا کوزے میں بند کرنے کا ایک محاورہ ہے اس کا صحیح مفہوم شاید
109
Page 118
سورۃ فاتحہ کے سوا اور کسی چیز سے ادا نہیں ہوسکتا.بلکہ اس سورۃ کے بارہ میں تو ہم کہ سکتے ہیں
کہ سمندر کوزہ میں بند کر دیا گیا ہے.غرض اسماء کے گنانے سے میرا منشاء پڑھنے والے کے ذہن کو ان وسیع مطالب کی طرف
توجہ دلانا تھا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ناموں کے ذریعہ سے اس سورۃ کے
بیان فرمائے ہیں ورنہ حقیقت سے خالی نام کسی سورۃ کے 9 چھوڑ 100 بھی ہوں تو ان سے
کوئی مقصد پورا نہیں ہوتا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بے فائدہ فعل ہر گز نہیں کر سکتے
تھے.پس سوچنے والوں کے لئے ان ناموں میں ایک اعلی روشنی اور کامل ہدایت ہے.حمدؐ اس سورۃ کے بہت سے فضائل حدیثوں میں بیان ہیں.نسائی نے ابی بن کعب سے
روایت کی ہے کہ رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا.اللہ تعالیٰ نے نہ توراۃ میں نہ انجیل
میں کوئی ایسی سورۃ اُتاری ہے جیسی کہ اُم القرآن ( یعنی سورۃ فاتحہ ) ہے اور اس کا ایک نام
السبع المثانی بھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بارہ میں مجھے فرمایا ہے کہ وہ میرے اور میرے
بندے کے درمیان بحضہ مساوی بانٹ دی گئی ہے اور اس کے ذریعہ سے میرے بندے جودُعا
مجھ سے کریں گے وہ ضرور قبول کی جائے گی.یہ فضیلت نہایت اہم ہے کیونکہ اس میں ایک عملی
گر بتایا گیا ہے جو انسان کے لئے دین ودنیا میں مفید ہے یعنی جو دُعا اس کے ذریعہ سے کی
جائے وہ قبول کی جاتی ہے.ظاہر ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر جو دعا کی جائے وہ ضرور قبول ہو جاتی
ہے.بلکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو ذریعہ دعا کا اس میں بتایا گیا ہے اس کا اختیار کرنا ضرور دعا کو
قبول کروادیتا ہے.اب سوال یہ ہے کہ وہ ذریعہ کیا ہے؟ جیسا کہ اس سورۃ کی عبارت سے ظاہر
ہے وہ ذریعہ اول بسم الله دوم الحمد للہ سوم الرحمن - چهارم الرحيم اور پنجم مُلكِ
يَوْمِ الدِّین اور ششم اِيَّاكَ نَعْبُدُ اور ہفتم اِيَّاكَ نَسْتَعِین ہے گویا جس طرح سات آیتوں
کی یہ سورۃ ہے اسی طرح سات اصول دُعا کی قبولیت کے لیے اس میں بیان کئے گئے ہیں.110
Page 119
بسم اللہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ جس مقصد کے لئے دُعا کی جائے وہ نیک ہو.یہ نہیں
کہ جور چوری کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو وہ بھی قبول کر لی جائے گی.خدا کا نام لے کر
اور اس کی استعانت طلب کر کے جودُعا کی جائے گی لازماً ایسے ہی کام کے متعلق ہوگی جس میں
اللہ کی ذات بندہ کے ساتھ شریک ہو سکتی ہو.میں نے بہت لوگوں کو دیکھا ہے لوگوں کی تباہی
اور بربادی کی دُعائیں کرتے ہیں اور پھر شکایت کرتے ہیں کہ ہماری دُعا قبول نہیں ہوئی.اسی
طرح ناجائز مطالب کے لئے دُعائیں کرتے ہیں اور پھر شکایت کرتے ہیں کہ دُعا قبول نہیں
ہوئی.بعض لوگوں نے جھوٹا جامہ زہد واثقا کا پہن رکھا ہے اور ناجائز امور کے لئے تعویذ دیتے
اور دُعائیں کرتے ہیں حالانکہ یہ سب دُعائیں اور تعویذ عاملوں کے منہ پر مارے جاتے ہیں.دوسرا اصل الْحَمدُ لِلهِ رَبِّ الْعَلَمین میں بتایا ہے یعنی دُعا ایسی ہو کہ اس کے نتیجہ میں خدا
تعالیٰ کے دوسرے بندوں کا بلکہ سب دنیا کا فائدہ ہو یا کم سے کم ان کا نقصان نہ ہو اور اس کے
قبول کرنے سے اللہ تعالیٰ کے حمد ثابت ہوتی ہو اور اس پر کسی قسم کا الزام نہ آتا ہو.تیسرے یہ کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت کو جنبش دی گئی ہو اور اس دُعا کے قبول کرنے
سے اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت ظاہر ہوتی ہو.چوتھے یہ کہ اس دُعا کا تعلق اللہ تعالیٰ کی صفت رحیمیت سے بھی ہو یعنی وہ نیکی کی ایک ایسی
بنیاد ڈالتی ہو جس کا اثر دنیا پر ایک لمبے عرصہ تک رہے اور جس کی وجہ سے نیک اور شریف لوگ
متواتر فوائد حاصل کریں یا کم سے کم ان کے راستہ میں کوئی روک نہ پیدا ہوتی ہو.پانچویں یہ کہ دُعا میں اللہ تعالیٰ کی صفت ملِكِ يَوْمِ الدّین کا بھی خیال رکھا گیا ہو.یعنی
دُعا کرتے وقت ان ظاہری ذرائع کو نظر انداز نہ کر دیا گیا ہو جو صحیح نتائج پیدا کرنے کے لئے
اللہ تعالیٰ نے تجویز کئے ہیں کیونکہ وہ سامان بھی اللہ تعالیٰ نے ہی بنائے ہیں اور اس کے بتائے
ہوئے طریق کو چھوڑ کر اس سے مدد مانگنا ایک غیر معقول بات ہے گویا جہاں تک اسباب
ظاہری کا تعلق ہے بشرطیکہ وہ موجود ہوں یا ان کا مہیا کر نا دُعا کرنے والے کے لئے ممکن ہوان
111
Page 120
کا استعمال بھی دُعا کے وقت ضروری ہے.ہاں اگر وہ موجود نہ ہوں تو پھر ملِكِ يَوْمِ الدّین کی
صفت اسباب سے بالا ہوکر ظاہر ہوتی ہے.ایک اشارہ اس آیت میں یہ بھی کیا گیا ہے کہ دُعا کرنے والا دوسروں سے بخشش کا معاملہ
کرتا ہو اور اپنے حقوق کے طلب کرنے میں سختی سے کام نہ لیتا ہو.چھٹا اصل یہ بتایا ہے کہ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ سے کامل تعلق ہو اور اس سے کامل اخلاص
حاصل ہو اور وہ شرک اور مشرکانہ خیالات سے کلی طور پر پاک ہو.اور ساتویں بات یہ بتائی ہے کہ وہ خدا کا ہی ہو چکا ہو اور اس کا کامل تو کل اسے حاصل ہو اور
غیر اللہ سے اس کی نظر بالکل ہٹ جائے اور وہ اس مقام پر پہنچ جائے کہ خواہ کچھ ہو جائے اور
کوئی بھی تکلیف ہو مانگوں گا تو خدا تعالیٰ ہی سے مانگوں گا.یہ سات امور وہ ہیں کہ جب انسان ان پر قائم ہو جائے تو وہ لِعَبْدِی مَا سَأَل کا مصداق ہو
جاتا ہے اور حق بات یہ ہے کہ اس قسم کی دُعا کا کامل نمونہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ
کے کامل اتباع نے ہی دکھایا ہے اور انہی کے ذریعہ سے دُعاؤں کی قبولیت کے ایسے نشان
دُنیا نے دیکھے ہیں جن سے اندھوں کو آنکھیں اور بہروں کو کان اور گونگوں کو زبان عطا ہوئی
ہے.مگر اشباع رسول کا مقام بھی کسی کے لئے بند نہیں.جو چاہے اس مقام کو حاصل کرنے
کے لئے کوشش کر سکتا ہے اور اس مقام کو حاصل کر سکتا ہے.بخاری نے سعید ابن المعنی سے ایک روایت کی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول کریم
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آؤئیں تمہیں قرآن کریم کی سب سے بڑی سورۃ سکھاؤں اور
پھر سورۃ فاتحہ سکھائی ( بخاری کتاب فضائل القرآن باب فاتحۃ الکتاب) آپ نے جو اسے
أعْظَمُ السُّوَر فرمایا تو اس کے یہی معنی ہیں کہ اس کے معانی اور مطالب لمبی لمبی سورتوں
سے بھی زیادہ ہیں اور کیوں نہ ہو کہ یہ سارے قرآن کریم کے لئے بطور متن کے ہے.سورۃ فاتحہ ہر نماز میں اور ہر رکعت میں پڑھنی ضروری ہے سوائے اس کے کہ مقتدی
112
Page 121
کے نماز میں شامل ہونے سے پہلے امام رکوع میں جا چکا ہو اس صورت میں اسے تکبیر کہہ کر بغیر
کچھ پڑھے رکوع میں چلے جانا چاہئے.امام کی قراءت ہی اس کی قراءت سمجھ لی جائے گی.سورۃ فاتحہ کے نماز میں پڑھنے کی تاکید مختلف احادیث میں آئی ہے.قرآن کریم کی سب سورتیں بسم اللہ الرّحمٰنِ الرَّحِیمِ سے شروع ہوتی ہیں.سوائے سورۃ براء ت کے مگر اس کے بارہ میں زیادہ صحیح قول یہی ہے کہ وہ الگ سورۃ نہیں بلکہ
سورۃ انفال کا تتمہ ہے اور اس لئے اس میں الگ بسم اللہ نہیں لکھی گئی.بسم اللہ کے متعلق بعض علماء نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ ہر سورۃ کا حصہ بسم اللہ نہیں بلکہ
صرف سورۃ فاتحہ کا حصہ بسم اللہ ہے اور بعض نے کہا ہے کہ کسی سورۃ کا حصہ بھی بسم اللہ نہیں ہے
لیکن یہ خیال درست نہیں.احناف کے متعلق جو بعض لوگ یہ خیال کرتے کہ وہ بسم اللہ کو گو یا قرآن کریم کا حصہ نہیں
سمجھتے.یہ غلط ہے.امام ابوحنیفہ کا یہ مذہب نہیں بلکہ یہ ہے کہ یہ آیت مستقل آیت ہے اور سورۃ
کا حصہ نہیں.امام ابوبکر رازی جو حنفیوں کے آئمہ سے ہیں اپنی کتاب احکام القرآن جزء اول میں
لکھتے ہیں کہ یہ آیت کسی سورۃ کا حصہ نہیں گو دوسورتوں کا فاصلہ بتانے کے لئے ایک مستقل آیت
کے طور پر اتاری گئی ہے.ہمیں اس کے ساتھ نماز شروع کرنے کا حکم بطور تبرک کے دیا گیا ہے.گومیرے نزدیک ان کا یہ عقیدہ بھی درست نہیں اور حق یہی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورۃ کا
حصہ ہے اور ہر سورۃ کے پہلے اس کے رکھنے میں بہت سی حکمتیں ہیں.بسم اللہ کی فضیلت پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص زور دیا ہے آپ فرماتے
ہیں کہ جس بڑے کام کو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکت ہوتا ہے.چنانچہ رسول
کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنت قائم کی ہے کہ مسلمان اپنے سب کاموں کو بسم اللہ سے
شروع کیا کریں.چنانچہ ایک حدیث ہے کہ اپنا دروازہ بند کرتے ہوئے بھی بسم اللہ کہہ لیا
کرو اور چراغ بجھاتے ہوئے بھی.اور برتن کو ڈھانکتے ہوئے بھی.اور اپنی مشک کا منہ
113
Page 122
باندھتے ہوئے بھی.اسی طرح بیوی کے پاس جاتے ہوئے.وضو کرتے ہوئے کھانا کھاتے
ہوئے.پاخانے میں داخل ہونے سے پہلے.لباس پہنتے ہوئے بسم اللہ کا کہنا احادیث سے
ثابت ہے.قرآن کریم میں حضرت سلیمان کے ایک خط کا ذکر کیا گیا ہے کہ انہوں نے بھی اپنا
خط بسم اللہ سے شروع کیا تھا.ہر سورۃ کے پہلے بشیر اللہ اس لئے رکھی گئی ہے کہ قرآن کریم کے متعلق یہ دعویٰ کیا
گیا ہے کہ یہ ایک خزانہ ہے جسے اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر نہیں کھولا جا سکتا.دوسری وجہ بسم الله الرّحمنِ الرَّحِيمِ کو ہر سورۃ کے پہلے رکھنے کی یہ ہے کہ بائبل میں
لکھا تھا کہ آخری زمانہ میں جو موسیٰ کا ایک مثیل آنے والا ہے.اس کے متعلق خدا تعالیٰ کا یہ
قانون ہو گا کہ ”جو کوئی میری باتوں کو جنہیں وہ میرا نام لے کے کہے گا نہ سنے گا تو میں اس کا
حساب اس سے لوں گا“ (استثناء باب 18 آیت 19 ) اس پیشگوئی کے مطابق مشیل موسی کے لئے
مقدر تھا کہ جب وہ خدا تعالیٰ کی باتیں کرے اس سے پہلے کہہ لے کہ میں یہ سب کچھ خدا تعالیٰ
کے نام پر کہہ رہا ہوں اپنی طرف سے نہیں.پس ضروری تھا کہ اس پیشگوئی کے مطابق ہر سورۃ
سے پہلے بسم اللہ رکھی جاتی تاکہ ایک طرف تو موسیٰ کی پیشگوئی پوری ہو اور دوسری طرف یہو داور
نصاری کو تنبیہ ہوتی رہے کہ اگر وہ اس کلام کو نہ سنیں گے تو موسیٰ علیہ السلام کے الہام کے
مطابق اللہ تعالیٰ کی سزا کے مورد بنیں گے.تیسری وجہ اس آیت کو ہر سورۃ کے شروع میں رکھنے کی یہ ہے کہ بائبل میں لکھا تھا وہ
نبی جو ایسی گستاخی کرے کہ کوئی بات میرے نام سے کہے جس کے کہنے کا میں نے اُسے حکم نہیں
دیا یا اور معبودوں کے نام سے کہے تو وہ نبی قتل کیا جاوے“ ( استثناء باب 18 آیت 20) اس
آیت میں بتایا گیا ہے کہ جو شخص خدا تعالیٰ کا نام لے کر کوئی جھوٹی بات کہے گا اسے اللہ تعالیٰ
بلاک کر دے گا.پس اس حکم کے مطابق قرآن کریم کی ہر سورۃ کی ابتدا میں بسم اللہ رکھی گئی تا کہ
یہود ونصاریٰ پر خصوصاً اور باقی دنیا پر عموما حجت ہو اور اس حکم کی موجودگی میں رسول کریم صلی اللہ
114
Page 123
علیہ وسلم کی کامیابی اور ترقی کو دیکھ کر ہر حق کا مثلاشی یہ سمجھ لے کہ آپ نے جو کچھ کہا خدا تعالیٰ
کی طرف سے کہا.اگر ایسا نہ ہو تو جب خدا تعالیٰ کا نام لے کر آپ نے اس کلام کو پیش کیا تھا
کیوں آپ بلاک نہ ہوئے.پس بسم اللہ یہود پر خصوصاً حجت ہے.ہر سورۃ کے پہلے بسم اللہ
رکھ کر گویا ایک سو چودہ دفعہ یہود کو ملزم بنایا گیا ہے اور محمد رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت
کی ایک سو چودہ دلیلیں پیش کی گئی ہیں.اگر صرف قرآن کریم کے شروع میں یہ آیت ہوتی تو
یہ بات حاصل نہ ہو سکتی تھی.چوتھی وجہ اس آیت کو ہر سورۃ کے شروع میں رکھنے کی یہ ہے کہ قرآن کریم کو پڑھنے والا
تین حال سے خالی نہیں یا تو وہ تہی دست اور بے سرمایہ ہوگا یا گناہوں کے ارتکاب سے خدا
تعالیٰ کی ناراضگی کو بھڑکا چکا ہو گا اور اللہ تعالیٰ کے فضل کو کھینچنے کا کوئی طبعی ذریعہ اس کے پاس
نہ ہوگا یا پھر وہ دین کی راہ میں قربانی کرنے والا ہوگا.یہ ظاہر ہے کہ ان
تینوں قسم کے لوگوں کی
قلبی کیفیت الگ الگ ہوگی.پہلی قسم کا انسان حیران دوسری قسم کا مایوس اور تیسری قسم کا مغرور
ہو سکتا ہے.پہلی قسم کا انسان اس حیرانی میں مبتلا ہوگا کہ میں کہاں سے صداقت تلاش کروں.دوسری قسم کا انسان اس غم میں گھلا جار ہا ہوگا کہ میں کس منہ سے مانگوں.اور تیسری قسم کا اس اثر
کے نیچے ہو گا کہ جو کچھ حاصل ہو سکتا تھا مجھے حاصل ہو گیا.دل کی ان تینوں کیفیتوں کے ماتحت
انسان نفع حاصل کرنے سے محروم رہ جاتا ہے.پس ہر سورۃ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم رکھا
گیا.تا جو تہی دست ہے اسے راستہ بتایا جائے کہ تہی دستوں کی مدد کرنے والا ایک خدا موجود
ہے جو بغیر استحقاق کے فضل کرتا ہے.اور جو نا فرمانی کر کے اپنا حق کھو چکا ہے اسے توجہ دلائی
جائے کہ مایوس نہ ہو.جس خدا نے یہ سورۃ اُتاری ہے وہ گناہوں کو بخشنے پر بھی آمادہ رہتا ہے
اور جو قربانی کی وجہ سے مغرور ہو رہا ہو اسے توجہ دلائی جائے کہ خدا تعالیٰ کی رحمتوں کے خزانے
غیر محدود ہیں.پس کسی ایک جگہ پر قدم نہ روک کہ ابھی غیر متناہی ترقیات باقی ہیں.ظاہر ہے کہ
دل کی اس قسم کی اصلاح کے بعد قرآنی مطالب جس طرح کھل سکتے ہیں اس کے بغیر نہیں کھل
115
Page 124
سکتے.پس ہر سورۃ سے پہلے اس آیت کو رکھ کر قرآنی مطالب کے اظہار کا ایک زبر دست
ذریعہ مہیا کیا گیا ہے.پانچویں وجہ اس آیت کو ہر سورۃ سے پہلے رکھنے کی یہ ہے کہ یہ ہر سورۃ کے لیے کنجی کا کام
دیتی ہے.تمام دینی اور روحانی مسائل رحمن اور رحیم دوصفات کے گرد چکر کھاتے
ہیں.چونکہ غلطی دو طرح دور ہوتی ہے کبھی تفصیل سے اور کبھی اجمال سے.اس لئے اللہ تعالیٰ
نے ہر سورۃ کے شروع میں بسم اللہ رکھ دی تاکہ سورۃ کے مطالب میں جو اشتباہ پیدا ہوا سے
پڑھنے والا بسم اللہ سے دُور کر لے.یعنی جو مطلب وہ سمجھتا ہے اگر رحمن اور رحیم کے مطابق ہو تو
اسے درست سمجھے اور اگر اس کے خلاف ہو تو اسے غلط قرار دے.اس طرح بسم اللہ کی شارح
سورۃ ہو جاتی ہے اور سورۃ کی مفتر بسم اللہ اور دونوں کی مدد سے صحیح مفہوم پڑھنے والے کے
ذہن نشین ہو جاتا ہے.ایک اور سوال اس جگہ پیدا ہوتا ہے کہ کہنا تو یہ چاہئے تھا کہ اللہ کی مدد مانگتے ہوئے
قرآن کریم پڑھتا ہوں اور کہا یہ گیا ہے کہ اللہ کے نام کی مدد سے پڑھتا ہوں.نام کا لفظ کیوں
زیادہ کیا گیا ہے؟ اس کے مفصلہ ذیل جواب ہیں.(1) باء استعانت کے علاوہ قسم کے لئے بھی آتی ہے اگر خالی باللہ ہوتا تو شبہ ہوسکتا تھا
کہ شائد قسم کھائی گئی ہے پس اس شبہ کے ازالہ کے لئے اسم کا لفظ بڑھایا گیا (2) اللہ تعالیٰ کی
ذات مخفی ہے اور صفات ہی سے وہ پہچانا جاتا ہے.اس لئے اسم کا لفظ بڑھایا گیا.الرحمن
الرحیم کے ذکر سے مراد بھی یہی ہے کہ میں خدا تعالیٰ سے اس کی رحمانیت اور رحیمیت کا
واسطہ دے کر مدد طلب کرتا ہوں (3) یہ توجہ دلائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں بھی
برکت ہے اور ان کی طرف انسان کو توجہ رکھنی چاہئے (4) قرآن کریم ایک بند خزانہ ہے اور
جب کوئی کسی ایسے مکان میں جس میں داخلہ بلا اجازت ممنوع ہو داخل ہوتا ہے تو اس کے
محافظوں کو یا مکین کو مالک کا حکم یا اجازت دکھاتا ہے یا اس کا ذکر کرتا ہے.چنانچہ پولیس
116
Page 125
جب کسی کے گھر میں داخل ہوتی ہے تو کہتی ہے کہ حکومت کے نام پر ہم داخل ہور ہے یا فلاں
مال پر قبضہ کرتے ہیں پس اس جگہ نام کا لفظ بڑھا کر اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جوشخص
بسم اللہ پڑھ کر قرآن کریم پڑھتا ہے وہ گویا قرآن کریم کی خدمت پر مامور فرشتوں سے کہتا
ہے کہ مجھے خدا تعالیٰ نے خود اس سورۃ کے پڑھنے کا حکم دیا ہے.پس میرے لئے اس کے
مطالب کے دروازے کھول دو اور وہ اختصاراً اس مضمون کو یوں ادا کرتا ہے کہ اللہ رحمٰن
رحیم کے نام پر اس خزانہ کے کھولے جانے کی میں درخواست کرتا ہوں.ظاہر ہے کہ جو
اس طرح خدا تعالیٰ کے اذن سے قرآن کریم کی طرف متوجہ ہو گا.اس کے علوم سے حصہ پائے
گا.لیکن جو اس کے اذن اور اس کے نام سے توجہ نہیں کرے گا بلکہ شرارت اور بغض سے توجہ
کرے گا اس کے لئے اس کے خزانے نہیں کھولے جائیں گے.پانچویں اور چھٹی حکمت اس کی ان دو پیشگوئیوں کی طرف اشارہ کرنا ہے جواستثناء آیت 18
اور آیت 20 میں مذکور ہیں اور جن کا ذکر میں اس سوال کی بحث میں کر آیا ہوں کہ ہر سورۃ کے
شروع میں بسم اللہ کیوں دہرائی گئی ہے اور وہ حکمت یہ ہے کہ ان پیشگوئیوں میں لکھا تھا کہ وہ
خدا کا نام لے کر کلام الہی سنائے گا.پس ان پیشگوئیوں کی طرف توجہ دلانے کے لئے ضروری
تھا کہ اسم کا لفظ اس جگہ بڑھایا جاتا.الحَمدُ لله.یہاں یہ نہیں فرمایا کہ میں اللہ کی حمد کرتا ہوں نہ یہ کہ ہم کرتے ہیں.بلکہ
الحمد اللہ فرمایا ہے.اس طرح کئی معانی پیدا کر دئیے گئے ہیں.اوّل مصدر کے استعمال سے
معروف اور مجہول دونوں معنی پیدا کر دئیے گئے ہیں.یعنی یہ بھی کہ سب حمد جو مخلوق کر سکتی ہے یا
کرتی ہے خدا تعالیٰ کو ہی پہنچتی ہے اور وہ سب قسم کی تعریفوں کا مستحق ہے.کوئی اچھی بات
نہیں جو اس میں نہ پائی جاتی ہو اور کوئی بری بات نہیں جس سے وہ پاک نہ ہو اور یہ بھی کہ اللہ
تعالی ہی مخلوق کی صحیح حمد کر سکتا ہے کیونکہ وہ عالم الغیب ہے.بندے بندے
کی تعریف کرتے
ہیں لیکن بسا اوقات وہ غلط ہوتی ہے بعض دفعہ جس قدر کسی میں خوبی ہوتی ہے.اس کا اظہار نہیں
117
Page 126
کر سکتے اور بعض دفعہ ایسی تعریف کرتے ہیں.جو موصوف میں پائی نہیں جاتی.پس اصل حمد
وہی ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے ہو بلکہ دوسرے لوگ تو الگ رہے انسان خود اپنی نسبت
رائے قائم کرنے میں غلطی کر جاتا ہے اور اپنی طاقتوں کا غلط اندازہ لگا لیتا ہے.مگر جو بات خدا
تعالیٰ بندہ کے متعلق فرماتا ہے نہ اس میں کوئی کمی ہوتی ہے نہ زیادتی.اگر الحمد کی بجائے
احمد یا محمد کے الفاظ ہوتے تو یہ معنی پیدا نہ ہو سکتے تھے.نیز اگر حمد کا صیغہ فعل استعمال کیا جاتا یعنی یہ کہا جاتا کہ میں اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہوں تو یہ شبہ ہو
سکتا تھا کہ شائد انسان اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کو سمجھنے کی قابلیت رکھتا ہے لیکن یہ درست
نہیں.انسان کی حمد محدود ہوتی ہے اور وہ صرف اپنے علم کے مطابق حمد کرتا ہے.حالانکہ اللہ
تعالیٰ میں اس کے سوا غیر محدود اسباب حمد کے اور بھی پائے جاتے ہیں.غرض احمد یا محمد سے جو معنے پیدا ہو سکتے تھے وہ بھی الحمد میں پائے جاتے ہیں اور ان
سے زائد بھی.اس لئے الحمد لله کے الفاظ کا اس مختصر سورۃ میں رکھنا جو سب مطالب کی جامع
ہے ضروری تھا.بیشک قرآن کریم میں حمد مخلوق کی طرف بھی منسوب ہوئی ہے جیسا کہ فرمایا
وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ (بقره (31) لیکن کہیں بھی احمد یا محمد کے الفاظ مخلوق کی طرف
منسوب نہیں ہوئے.گو نُسَبِّحُ اور نُقَدِّسُ کے الفاظ یا یسبح کے الفاظ استعمال ہوئے
ہیں اس میں اس امر کی طرف لطیف اشارہ ہے کہ خالص حمد کا مکمل طور پر سمجھنا بندہ کی شان سے بالا
ہے.حدیثوں میں یہ الفاظ آتے ہیں.مگر ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ کے کلام میں الفاظ کے اور معنے
ہوتے ہیں اور بندہ کے کلام میں اور.بندہ جب اپنی طرف سے ایک لفظ بولتا ہے تو اس کے
معنے اتنے وسیع نہیں لئے جاتے جتنے وسیع کہ اس وقت لئے جاتے ہیں جب خدا تعالیٰ کے کلام
اور پھر کلام شریعت میں وہ الفاظ آئیں.لله کے الفاظ سے اس شبہ کو بھی ڈور کیا ہے کہ حمد تو انسانوں کی بھی کی جاتی ہے.پھر
سب تعریف خدا تعالیٰ کی کس طرح ہوئی ؟ اور وہ اس طرح کہ لام ملکیت ظاہر کرنے کے لئے
118
Page 127
آتا ہے.پس لام کے ذریعہ سے یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد حقیقی ہوتی ہے اور غیر اللہ کی
طفیلی.کیونکہ انسان میں جو خوبیاں پائی جاتی ہیں.ذاتی نہیں ہوتیں.بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے
اسے عطا شدہ ہوتی ہیں.پس جو تعریف کسی انسان کی کی جاتی ہے اس کا بھی اصل مستحق
اللہ تعالی ہی ہوتا ہے.اس آیت کے بعض مطالب ذیل میں لکھے جاتے ہیں:
(1) اس جہان کا خالق سب نقصوں سے پاک اور سب خوبیوں کا جامع ہے.(2) وہ تمام مخلوق کی گنہ اور حقیقت سے واقف ہے اور اس کے سوا کوئی شخص بھی کسی چیز کی
کامل ماہیت سے واقف نہیں.اس دعویٰ کا روشن ثبوت سائنس کی ترقی سے مل چکا ہے.مختلف
اشیاء کی تحقیق میں سینکڑوں علماء لگے ہوئے ہیں لیکن اب تک ادنیٰ سے ادنی شے کی کامل حقیقت سے
بھی کوئی آگاہ نہیں ہوسکا.اور ہر چیز کے متعلق تازہ انکشافات ہوتے چلے جارہے ہیں.(3) خدا تعالی کامل حمد کا مالک تب ہی ہو سکتا ہے کہ وہ رَبُّ الْعَالَمِین ہو.اگر رَبُّ
العالمین نہ ہو تو وہ کامل حمد کا مالک نہیں ہو سکتا.اس لئے ضروری ہے کہ جس طرح اس کا
جسمانی نظام سب کے فائدہ میں لگا ہوا ہے.اس کا روحانی نظام بھی سب پر حاوی ہو.اور کوئی
ملک اور کوئی قوم روحانی ترقی کے سامانوں سے محروم نہ ہو.پس اگر کوئی الہام کسی خاص قوم
سے مختص ہے.تو دوسری قوم کے لئے الگ الہام نازل ہونا چاہئے.اور جب دوسری قوموں
کے لئے الگ الہام نازل نہ ہو.تو ایسے وقت میں جو الہام نازل ہو وہ سب دنیا کی ہدایت کے
لئے ہونا چاہئے (پس جو مذاہب اس امر کے قائل ہیں کہ الہام صرف انہی کی قوم کی ہدایت
کے لئے نازل ہوا ہے.یا یہ کہ نجات صرف انہی کی قوم یا مذہب کا حق ہے غلطی پر ہیں)
(4) انسانوں کے اندر جس قدر کمالات ہیں وہ سب خدا تعالیٰ کے عطا کردہ ہیں.اس لئے
جو نیکی بھی وہ کریں اس کی تعریف کا حقیقی مستحق اللہ تعالیٰ ہی ہے.(5) حمد کو ربوبیت عالمین کے ساتھ وابستہ کر کے یہ بتایا ہے کہ حقیقی خوشی انسان کو اسی
119
Page 128
وقت ہونی چاہئے جب اللہ تعالیٰ کی صفت رب العالمین ظاہر ہو.جوشخص اپنے فائدہ پر خوش ہوتا
ہے اور دُنیا کے نقصان کی طرف نگاہ نہیں کرتا.وہ اسلام کی تعلیم کو نہیں سمجھتا.حقیقی خوشی یہی ہے
کہ سب دنیا آرام میں ہو.(6) یہ فرما کر کہ اللہ تعالیٰ رَبُّ العالمین ہے.اس طرف اشارہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ
کے سوا ہر شے ربوبیت کا محل ہے یعنی ارتقا کے قانون کے ماتحت ہے.یہ بتایا ہے کہ دنیا میں
کوئی چیز نہیں جس کی ابتدا اور انتہا یکساں ہو.بلکہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز تغیر پذیر ہے.اور
ادمی حالت سے ترقی کر کے اعلیٰ کی طرف جاتی ہے.جس سے دو امر ثابت ہوتے ہیں.اوّل
خدا تعالیٰ کے سوا ہر شے مخلوق ہے کیونکہ جو چیز ترقی کرتی اور تغیر پکڑتی ہے وہ آپ ہی آپ نہیں
ہوسکتی.دوسرے ارتقا کا مسئلہ درست ہے.ہر شے ادنیٰ حالت سے اعلیٰ کی طرف گئی ہے خواہ
انسان ہوں خواہ حیوان.خواہ نباتات ہوں خواہ جمادات.کیونکہ رب العالمین کے معنی یہ ہیں کہ
ہر شے کو ادنیٰ حالت سے اعلیٰ کی طرف لے جا کر اللہ تعالیٰ کمال تک پہنچاتا ہے پس ثابت ہوا
کہ ارتقا کا مسئلہ دنیا کی ہر شے میں جاری ہے.(7) نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ ارتقا مختلف وقتوں اور مدارج (STAGES) میں حاصل ہوتا
ہے.کیونکہ رب کے معنی ہیں.اِنْشَاءُ الشَّيْء حَالًا فَحَالًا إلى حَدِ التَّمامِ چیز کو مختلف
وقتوں اور مختلف درجوں میں ترقی دیکر کمال تک پہنچانا ( نہ کہ ایک ہی کڑی کو مکمل کرنا ).(8) یہ بھی معلوم ہوا کہ ارتقا اللہ تعالیٰ کے وجود کے منافی نہیں.کیونکہ فرمایا کہ الحمد لله
رب العالمین ارتقا کے ذریعہ سے پیدائش خدا تعالیٰ کے عقیدہ کے خلاف نہیں پڑتی.بلکہ
اس سے وہ حمد کا مستحق ثابت ہوتا ہے.اسی لئے ربّ العالمین کے ساتھ الحمد الله کے
الفاظ استعمال فرمائے.(9) اس آیت میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ انسان کو لامتناہی ترقیات کے لئے پیدا کیا
120
Page 129
گیا ہے.کیونکہ فرماتا ہے کہ سب تعریف اللہ تعالیٰ کی ہے کہ وہ مختلف انواع و اقسام کی
مخلوق کو ادنی حالت سے اٹھا کر اعلیٰ تک پہنچاتا ہے اور یہ مضمون صحیح نہیں ہوسکتا جب تک ہر
مقام اور درجہ سے اوپر کوئی اور درجہ تسلیم نہ کیا جائے.(10) سب سے آخر میں یہ کہ اس سورۃ کو جو سب سے پہلی سورۃ ہے اور قرآن کریم کے
مطالب کا خلاصہ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سے شروع کر کے یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی
کامل حمداب شروع ہوگی کیونکہ اسلام جو رَبُّ العالمین کی صفت کا کامل مظہر ہے سب دنیا
کی طرف آیا ہے اور جسمانی عالم کی طرح روحانی عالم میں بھی اتحاد پیدا کر دیا گیا ہے.پہلے
جب مختلف اقوام کی طرف الگ رسول آتے تھے بعض نادان متبع دوسرے انبیاء کی تعلیم کو غلط
سمجھ کر ان کی تردید کرتے تھے.ہندو کہتے ہم یہووا کو نہیں جانتے ، پرمیشور کو جانتے ہیں.یہود
پرمیشور پر ہنسی اڑاتے.لیکن اسلام کے ظہور سے سب دنیا کے لئے ایک دین ہو گیا.اور
ہندی اور چینی اور مصری اور ایرانی اور مغربی اور مشرقی سب خدا کی تعریف میں لگ گئے اور یہ
تسلیم کیا گیا کہ ہر قوم کا خدا الگ نہیں ہے بلکہ سب اقوام کا خدا ایک ہی ہے.الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ان دونوں صفات کا ذکر بِسمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ
الرَّحِيمِ میں ہو چکا ہے پھر ان کو دُہرایا کیوں گیا ہے.اس کا جواب یہ ہے کہ بسم اللہ
میں ایک مستقل مضمون بیان ہوا ہے اور وہ ہر سورۃ کی کنجی ہے.اس لئے سورۃ کے مضمون میں
اگر اپنے موقعہ پر انہی صفات کو دوبارہ بیان کیا جائے.تو یہ امر تکرار نہیں کہلا سکتا.چنانچہ یہاں
بھی اسی حکمت سے ان صفات کو دُہرایا گیا ہے.رَبُّ الْعَالَمِينَ میں یہ مضمون بتایا گیا تھا
کہ خدا تعالیٰ پیدا کر کے آہستہ آہستہ اور درجہ بدرجہ اعلیٰ ترقیات تک پہنچاتا ہے.آیت زیر
تفسیر میں الرحمٰنِ الرَّحِیم کے الفاظ سے طریق ربوبیت بتایا ہے اور وہ یہ کہ
(1) اللہ تعالیٰ رحمن ہے اس نے ہر چیز کے لئے ایسے سامان پیدا کئے ہیں جو اس کی
121
Page 130
ترقی میں محمد ہوتے ہیں اور بار یک دربار یک سامان پیدا کر کے مخفی در مخفی قوتوں کو قوت ظہور
عطا فرمائی ہے.اور ترقی کے ذرائع بہم پہنچائے ہیں.انسان حیوان نباتات جمادات سب اپنے گردو
پیش سے
متاثر ہور ہے ہیں.اور اپنے قیام یا اپنی تکمیل کے سامان حاصل کر رہے ہیں.(2) و رحیم ہے پس جب کوئی مخلوق اپنے فرائض کو اچھی طرح ادا کرتی ہے تو اس کی
قدر دانی کی جاتی ہے اور اس پر خاص فضل کیا جاتا ہے اور مزید ترقی کی اس میں اُمنگ پیدا کی
جاتی ہے اور اسی طرح یہ سلسلہ لامتناہی طور پر چلا جاتا ہے.الرحمن.ایسی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اس کا استعمال دوسروں پر نہیں ہوتا سوائے
اضافت کے جیسا کہ مسلیمہ کذاب اپنے آپ کو رحمن یمامہ کہلواتا تھا.اس کے معنی جیسا کہ
بتایا جا چکا ہے بلا مبادلہ اور بلا استحقاق رحم کرنے کے ہیں.اور اس مفہوم میں کفارہ کا رد پایا جاتا
ہے.کیونکہ کفارہ کی بنیاد اس خیال پر ہے کہ اللہ تعالیٰ بلا استحقاق رحم نہیں کر سکتا.مسیحیوں کو اس
کا اس قدر احساس ہے کہ عرب کے نصاریٰ بھی جب اپنی تصنیفات یا خطوں پر خدا تعالیٰ کا نام
لکھتے ہیں تو بسم اللہ کے بعد اور صفات کا ذکر کر دیتے ہیں.رحمن کا لفظ استعمال نہیں کرتے.سوائے ایسے شخص کے جو اسلامی تمدن سے متاثر ہو.مثلاً یہ لکھ دیں گے.بسم اللہ الکریم
الرَّحِیم یا اور کوئی صفت بیان کر دیں گے.رحمن کا لفظ استعمال نہیں کریں گے.کیونکہ
ان کا دل مانتا ہے کہ اگر خدا تعالیٰ رحمن ہے تو پھر اس کے لئے مسیح کا کفارہ لئے بغیر بندوں کے
گناہ بخشنا کچھ بھی مشکل نہیں.رحیم کی صفت میں تناسخ کارڈ ہے.کیونکہ تناسخ کی بنیاد محدود عمل کی غیر محدود جزا نہ مل
سکنے کا عقیدہ ہے.صفت رحیم بتاتی ہے کہ محدود عمل کی غیر محدود جز انہیں ملتی بلکہ نیک عمل کی
خاصیت یہ ہے کہ وہ مکر رہوتا ہے.پس اس کے بدلہ میں جزا بھی مکر ملتی ہے.رحیم کا لفظ
بار بار رحم کرنے پر دلالت کرتا ہے اور بار بار رحم کے معنے یہ نہیں کہ ایک ہی فعل کا بار بار انعام
ملتا ہے بلکہ اس سے یہ مراد ہے کہ جو شخص نیکی کی حقیقت کو سمجھتا ہے وہ بار بار نیک اعمال بجالاتا
122
Page 131
ہے اور کم سے کم اس کے دل میں بار بار نیک عمل بجالانے کی خواہش ضرور پائی جاتی ہے.پس
ہر دفعہ جب نیک عمل کی جزا بندہ کوملتی ہے اور نیکی کرنے کی طاقت اور اس کے بار بار بجالانے
کی خواہش اور بھی ترقی کر جاتی ہے جس کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ اس پر پھر رحم کرتا ہے اور مومن کی
نیکی کی خواہش اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے اور وہ نیکی کے کاموں میں اور بھی بڑھ جاتا ہے اور اس
طرح رحم بار بار نازل ہوتا جاتا ہے.گو یا اللہ تعالیٰ کا رحم صرف گذشتہ فعل پر انعام کا رنگ ہی
نہیں رکھتا بلکہ آیندہ نیکی کے لئے ایک بیج کا کام بھی دیتا ہے.در حقیقت محدود عمل کا خیال ہندوؤں میں محض اس وجہ سے پیدا ہوا ہے کہ انہوں نے جنت
کو بیکاری اور بے عملی کا ایک مقام سمجھ لیا ہے اور ان کو سمجھنا بھی ایسا ہی چاہئے کیونکہ وہ نجات
کے معنی نروان یعنی تمام خواہشات اور اعمال سے آزاد ہونا سمجھتے ہیں.پس ان کے نزدیک عمل
اسی دنیا میں ختم ہو جاتا ہے اور اس وجہ سے محدود ہوتا ہے.اور چونکہ عمل محدود ہوتا ہے ان کے
نزدیک اس کا بدلہ بھی محدود ہونا چاہیئے.مگر اسلام بار بار رحم اور بار بار عمل کے مسئلہ کو پیش کرتا
ہے اور جنت کو دارالعمل ہی قرار دیتا ہے.جب خدا تعالیٰ رب العالمین ہے تو جنت بھی تو
ایک عالم ہے وہاں بھی ترقی ہوگی.ورنہ رب العالمین صحیح نہیں ٹھہرتا.اور جب انسان وہاں بھی
ترقی کرے گا تو لازماً اس کے تقویٰ اور اس کی محبت الہی میں بھی ترقی ہوگی اور جب ان چیزوں
میں ترقی ہو گی تو اس ترقی کے مقابل پر اللہ تعالیٰ کا رحم بھی پھر سے نازل ہوگا.اور جب یہ رحم اور
عمل کا بار بار تبادلہ ہوتا رہے گا تو نجات کا وقت محدود کس طرح ہو سکتا ہے.اس دنیا اور اگلے
جہاں کے عمل میں صرف یہ فرق ہے کہ اس دنیا میں تنزل کا خطرہ بھی ساتھ لگا ہوا ہے.مگر اگلے
جہان میں صرف ترقی ہوگی تنزیل نہ ہو گا.ورنہ روحانی عمل اور روحانی ترقی وہاں بھی ہوگی.پس
محدود عمل اور غیر محدود جزاء کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا.مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ
مالِكُ مَلَكُ اور مَلِكُ تين ملتے جلتے لفظ ہیں.مالک جسے کسی چیز پر جائز قبضہ اور
123
Page 132
اقتدار حاصل ہو.ملک فرشتہ.اور ملك بادشاہ یعنی جسے سیاسی اقتدار حاصل ہو.يوم.اس کے معنی مطلق وقت کے ہوتے ہیں قرآن کریم میں ہے.اِنَّ يَوْمًا عِنْدَ
رَبَّكَ كَالْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ (الحج 48) خدا تعالیٰ کا بعض دن ہزار سال کا ہوتا ہے.سیبویہ کا قول ہے کہ عرب کہتے ہیں.انا الْيَوْمَ أَفْعَلُ كَذَا لَا يُرِيدُونَ يَوْمًا بِعَيْنِهِ
وَلَكِنَّهُمْ يُرِيدُونَ الْوَقْتَ الْحَاضِرَ (لسان العرب) یعنی جب کہتے ہیں کہ میں آج کے
دن اس اس طرح کروں گا.تو اس سے مراد چوبیس گھنٹہ والا دن نہیں ہوتا.بلکہ اس سے مراد
صرف موجودہ وقت ہوتا ہے.اسی طرح الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ جو قرآن کریم میں
آتا ہے.اس سے بھی مُراد معروف دن نہیں بلکہ زمانہ اور وقت مراد ہے (لسان العرب ) پھر
لکھا ہے وَقَد يُرَادُ بِالْيَوْمِ الْوَقْتُ مُطلَقًا وَمِنْهُ الْحَدِيثُ تِلْكَ آيَامُ الْهَرَجِ أَىٰ وَقْتُهُ
(لسان العرب) یعنی کبھی یوم سے مطلق وقت مراد ہوتا ہے جیسے حدیث میں ہے کہ یہ دن فتنہ
اور لڑائی کے دن ہیں.مراد یہ کہ یہ فتنہ اور لڑائی کا زمانہ ہے.* الدِّينُ الْجَزَاء وَالْمُعَافَأَةُ بدله - الطاعَةُ اطاعت.الحِسَابُ.محاسبہ.الْقَهْرُ وَ الْغَلَبَةُ وَالْإِسْتِعْلَاءُ غَلَبَةُ السُّلْطَانِ وَالْمَلِكِ وَالْحُكُم.تصرف
حکومت - السيرَةُ - خصلت - التَّدْبِيرُ - تدبير - اسم لِلجَمِيعِ مَا يُعْبَدُ بِهِ اللهُ وه تمام
طریقے جن سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے وہ سب دین کہلاتے ہیں.یعنی شریعت.نیز
اس کے معنی ہیں الْمَلةُ مذہب - اَلْوَرَعُ نیکی.الْمَعْصِيَةُ نافرمانی - اَلْحَالُ - کیفیت.الْقَضَاءُ فیصلہ - الْعَادَةُ عادت الشأن خاص حالت (اقرب)
آیت کے یہ معنی ہوئے کہ اللہ تعالیٰ جزا سزا کے وقت کا مالک ہے.شریعت کے وقت
کا مالک ہے.فیصلہ کے وقت کا مالک ہے.شریعت کے وقت کا مالک ہے.مذہب
کے زمانہ کا مالک ہے.نیکی کے زمانہ کا مالک ہے.گناہ کے زمانہ کا مالک ہے.محاسبہ
کے وقت کا مالک ہے.اطاعت کے وقت کا مالک ہے.غلبہ کے وقت کا مالک ہے.124
Page 133
خاص اور اہم حالتوں کا مالک ہے.عام طور پر تو اس کے معنی قیامت کے دن کا مالک کئے جاتے ہیں لیکن جیسا کہ لغت سے
ظاہر ہے.یہ معنی محض تفسیری ہیں لغوی نہیں.دین کے ایک معنی جز اسزا کے ہیں.اور جزا سزا
کا کامل مظاہرہ چونکہ قیامت کے دن ہو گا اس لئے مفسرین نے جزا سزا کے معنوں کی بنیاد پر
اس آیت کے یہ معنی کر دئیے کہ قیامت کے دن کا مالک ہے.حالانکہ لغت کے رو سے اس
آیت کے مختلف معنی ہوتے ہیں اور سب کے سب قرآنی مطالب کے مطابق اور درست
ہیں.پس کوئی وجہ نہیں کہ ایک معنوں کو تو لے لیا جائے اور دوسروں کو چھوڑ دیا جائے.ملِكِ يَوْمِ الدین سے یہ مراد نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس دُنیا کا مالک نہیں ہے بلکہ اگر
اس آیت کے معنی قیامت کے دن کے مالک کے کئے جائیں تب بھی آیت کا مطلب یہ ہے
کہ اس دن ظاہری طور پر بھی کوئی مالک نہ ہو گا جیسا کہ فرمایا وَمَا أَدْرَكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ
ثُمَّ مَا ادْرُكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْاَ مُرُ يَوْمَئِذٍ لِلهِ
(انفطار 20) یعنی تم کو کیا معلوم کہ یوم الدین کیا ہے.یوم الدین وہ دن ہے کہ کوئی شخص
دوسرے کے کسی کام نہ آ سکے گا.اور صرف خدا تعالیٰ کا حکم جاری ہوگا.پس مالک سے مراد یہ
ہے کہ اس دُنیا میں جو ظاہر میں بادشاہ اور حاکم اور مالک نظر آتے ہیں.یہ سلسلہ اگلے جہان
میں ختم ہو جائے گا.اور یہ مراد نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس جہان کا مالک نہیں ہے.إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ
الحمد الله سے لے کر ملِكِ يَوْمِ الدّین تک کی عبارت سے یوں ظاہر ہوتا ہے کہ
گویا خدا تعالیٰ بندہ کی نظر سے اوجھل ہے اور وہ اس کی تعریف کر رہا ہے.لیکن اِيَّاكَ نَعْبُدُ
سے یک دم خدا تعالیٰ کو مخاطب کر لیا گیا ہے بعض نادانوں نے اس پر اعتراض کیا ہے کہ یہ
حسنِ کلام کے خلاف ہے.حالانکہ یہ حسن کلام کے خلاف نہیں بلکہ حسن کلام کی ایک اعلیٰ مثال
ہے.اللہ تعالیٰ کی ذات وراء الوراء ہے وہ بندہ کو نظر نہیں آتی.اس کی صفات کے ذریعہ سے
125
Page 134
وہ اسے شناخت کرتا ہے.اور اس کے ذکر کے ذریعہ سے وہ اس کے قریب ہوتا ہے یہاں
تک کہ اس کے دل کی آنکھیں اسے دیکھ لیتی ہیں.ان آیات میں سلوک کے اس نکتہ کو بیان
کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ رَبُّ الْعَالَمِینَ رَحْمَن رَحِيم مُلِكِ يَوْمِ الدِّین کی
صفات پر جب انسان غور کرتا ہے تو اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی محبت شدید طور
پر اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے تب وہ روحانی طور پر اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف اور
اس کی محبت سے مغلوب ہو کر بے اختیار چلا اٹھتا ہے کہ اے رب میں تیری ہی عبادت کرتا
ہوں اور تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں.پس اس طرح ضمائر کو بدل کر اس مضمون کی طرف اشارہ کیا
گیا ہے کہ قرآن کریم میں بتائی ہوئی صفات پر غور کرنے سے انسان کو اللہ تعالیٰ کی ملاقات
حاصل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات بندہ کے سامنے آ جاتی ہے.اس آیت میں نَعْبُدُ پہلے ہے اور نَسْتَعِين بعد میں.بعض لوگ اس پر اعتراض
کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی عبادت کی توفیق تو اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہی حاصل ہوسکتی ہے.پھر
نعبد کو پہلے کیوں رکھا؟ نَسْتَعِین پہلے چاہئے تھا.اس کا جواب یہ ہے کہ بیشک عبادت بھی اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہوتی ہے لیکن اس جگہ
اعانت کا ذکر نہیں بلکہ استعانت کا ذکر ہے یعنی مدد مانگنے کا.اور اس میں کیا شک ہے کہ جب
بندہ کے دل میں عبودیت اور عبادت کا خیال پیدا ہو گا اس کے بعد ہی وہ اللہ تعالیٰ سے دُعا
مانگنے کا خیال کرے گا.جو عبادت کی طرف راغب ہی نہ ہو وہ مدد کیوں طلب کرے گا.پس گو
اللہ تعالیٰ کے فضل اور اعانت کے بغیر عبادت کی توفیق نہیں ملتی لیکن استعانت یعنی بندہ کا اللہ
تعالیٰ کے دروازہ پر جھکنا عبادت کا خیال آنے کے بعد ہی پیدا ہوتا ہے.اس وجہ سے نعبد کو
پہلے اور نستعین کو بعد میں رکھا گیا ہے.دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ ارادہ بندہ کی طرف سے ہوتا ہے اور عمل کی توفیق اللہ تعالیٰ کی
طرف سے.اگر ارادہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو تو انسان کے اعمال اضطراری اعمال ہو
جائیں.پس اس آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ جب بندہ کے دل میں عبادت کا خیال پیدا ہو.126
Page 135
اسے اللہ تعالیٰ سے تکمیل ارادہ کے لئے دُعا کرنی چاہئے اور کہنا چاہئے کہ اے میرے رب میں
تیری عبادت کا فیصلہ کر چکا ہوں.مگر اس عہد کی تکمیل تیری امداد کے سوا نہیں ہو سکتی.اس لئے
تو میری مدد کر اور مجھے اس امر کی توفیق دے کہ تیرے سوا کسی کی عبادت نہ کروں.عبادت کامل تذلیل کا نام ہے.پس عبادت کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو
بندہ اپنے اندر پیدا کر لے.عبادت کی ظاہری علامات صرف قلبی کیفیت کو بدلنے کے لئے
مقرر ہیں.ورنہ اس میں کوئی شک نہیں کہ عبادت دل کی کیفیت اور اس کے ماتحت انسانی
اعمال کے صدور کا نام ہے اور خاص اوقات کی تعیین اور قبلہ رو ہونا اور ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا یا
رکوع سجود کرنا یہ اصل عبادت نہیں بلکہ جسم کی ظاہری حالت کا اثر چونکہ دل پر ہوتا ہے اور توجہ بھی
قائم ہوتی ہے اس لئے نماز کے لئے کچھ ظاہری علامات بھی مقرر کر دی گئی ہیں.مگر وہ بمنزلہ برتن
کے ہیں جس میں معرفت کا دودھ ڈالا جاتا ہے یا بطور چھلکے کے ہیں جس میں عبادت کا مغز رہتا ہے.اس آیت میں اور بعد کی آیات میں جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے.یعنی یوں کہا گیا
ہے کہ ”ہم عبادت کرتے ہیں“ اور ”ہم مدد مانگتے ہیں“ اور ”ہمیں سیدھا راستہ دکھا اس میں
اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ اسلام ایک مدنی مذہب ہے وہ سب کے لئے ترقی چاہتا ہے نہ
کہ کسی ایک شخص کے لئے.اور یہ بھی کہ ہر مسلمان دوسرے کا نگران مقرر کیا گیا ہے.اس کا
یہی کام نہیں کہ وہ خود عبادت کرے بلکہ یہ بھی ہے کہ دوسروں کو عبادت کی تحریک کرے او
راس وقت تک تحریک نہ چھوڑے جب تک وہ اس کے ساتھ عبادت کرنے میں شامل نہ ہو
جائیں.اور وہ آپ ہی اللہ تعالیٰ پر توکل نہ کرے بلکہ دوسروں کو بھی تو کل کی تعلیم دے اور اس
وقت تک بس نہ کرے جب تک وہ تو کل میں اس کے ساتھ شامل نہ ہو جائیں اور وہ خود ہی
ہدایت کا طالب نہ ہو بلکہ دوسروں کو بھی ہدایت طلب کرنے کی نصیحت کرے.اور بس نہ کرے
جب تک ان کے دل میں بھی ہدایت طلب کرنے کی تڑپ پیدا ہو کر وہ اس کے ساتھ شامل نہ ہو
جائیں.اور خود بھی ہر دعا میں ”میں“ کی جگہ ہم کا لفظ استعمال نہ کرنے لگیں.یہی تبلیغی اور تربیتی
روح ہے جس نے اسلام کو چند سالوں میں کہیں کا کہیں پہنچا دیا.اور ا گر آج مسلمان ترقی کر
127
Page 136
سکتے ہیں تو صرف اسی جذبہ کو اپنے دل میں پیدا کر کے جب تک مسلمان نَعْبُدُ اور نَسْتَعِين
اور اھینا کے الفاظ نہیں کہتے.جب تک ان الفاظ کو سچے طور پر کہنے کے لئے جدو جہد نہیں
کرتے اس وقت تک ان کا نہ دین میں ٹھکانا ہوگا نہ دُنیا میں.حقیقت یہ ہے کہ عبادت بھی اور استعانت بھی اور طلب ہدایت بھی بحیثیت جماعت ہی
ہوسکتی ہے کیونکہ اکیلا آدمی صرف ایک محدود عرصہ کے لئے اور ایک محدود دائرہ میں عبادت کو
قائم کر سکتا ہے.ہاں جو اپنی اولاد کو بھی اور اپنے ہمسائیوں کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیتا ہے وہ
عبادت کا دائرہ وسیع کر دیتا ہے اور اس کا زمانہ ممتد کر دیتا ہے اور اس میں کیا شبہ ہے کہ سچا
عبدو ہی ہے جو اپنے آقا کی مملوکہ اشیاء کو دشمن کے ہاتھ میں نہ پڑنے دے.جو اپنے آقا کے
باغ کو لٹتے دیکھتا اور اس کیلئے جدوجہد نہیں کرتا وہ ہر گز سچابندہ نہیں کہلا سکتا.إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کی آیت میں جبر اور قدر کے متعلق جو غلط خیالات
لوگوں میں پھیل رہے ہیں ان کا بھی رد کیا گیا ہے.انسانی اعمال کے بارہ میں لوگوں میں دو
غلط فہمیاں پیدا ہیں.بعض تو یہ کہتے ہیں کہ جس قدر اعمال انسان سے سرزد ہو رہے ہیں جبر کے
ماتحت ہیں یعنی انسان ان کے کرنے پر مجبور ہے.یہ خیال مذہبی لوگوں میں بھی ہے اور
فلسفیوں میں بھی.اور اب علم النفس کے ماہرین کا ایک گروہ بھی ایک رنگ میں اس کا قائل ہو
رہا ہے اور ان کا سردار ڈاکٹر فرائڈ آسٹرین پروفیسر ہے.جولوگ اس عقیدہ پر غلط مذہبی عقیدہ
کی وجہ سے قائم ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ اللہ تعالی مالک ہے جس طرح ایک انجینئر جب
عمارت بناتا ہے تو کسی اینٹ کو پاخانہ میں اور کسی کو بالا خانہ میں لگاتا ہے.اسی طرح اللہ تعالیٰ
مختار ہے کہ جسے چاہے نیک بنائے اور جسے چاہے بدکار بنائے.سواس نے بعض کو نیک اور
بعض کو بدکار بنایا ہے.مسیحیوں نے ورثہ کا گناہ تسلیم کر کے جبر کے مسئلہ کو رائج کیا ہے.کیونکہ جب انسان ورثہ کے گناہ سے کفارہ کے بغیر آزاد نہیں ہو سکتا تو جس قدر لوگ کفارہ پر
ایمان نہیں لاتے گنہگار ہونے پر مجبور ہیں.تناسخ کا مسئلہ بھی جبر کی تائید میں ہے.کیونکہ جو
جون سابق گناہ کی سزا میں ملی ہے لازماً ان حد بندیوں کے نیچے رہے گی جو سابقہ گناہ کی وجہ سے
128
Page 137
اس پر لگا دی گئی ہیں.فلسفیوں کے عقیدہ کی بنیا د صرف تجر بہ پر تھی کہ باوجود کوشش کے بعض
لوگ گناہ سے بچ نہیں سکتے.لیکن ڈاکٹر فرائڈ نے اس مسئلہ کو علمی مسئلہ بنا دیا ہے.اس کا
خیال ہے کہ چونکہ انسان کی تعلیم کا زمانہ اس کے ارادہ کے زمانہ سے پہلے شروع ہوتا ہے یعنی
بچپن سے.اور ارادہ اور اختیار بلوغ کے وقت پیدا ہوتا ہے.اس لئے نہیں کہہ سکتے کہ اس کا
ارادہ آزاد ہے.بلکہ جس چیز کو ہم ارادہ کہتے ہیں درحقیقت وہ وہی میلان ہے جو بچپن کے
اثرات کے نتیجہ میں اس کے اندر پیدا ہو گیا ہے.انسان اپنے افعال کو با ارادہ اور خیالات کو
آزاد سمجھتا ہے لیکن درحقیقت وہ صرف بچپن کے تاثرات کے نتائج ہیں.اور چونکہ وہ اس کے
نفس کا جزو بن گئے ہیں اس لئے وہ اسے بیرونی اثر خیال نہیں کرتا بلکہ اپنا ارادہ سمجھتا ہے.ڈاکٹر فرائڈ کے یہ خیالات نئے نہیں.اسلام میں ان کی سند ملتی ہے جیسے کہ رسول کریم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے.مگر آبَوَاهُ يُهوِدَانِهِ
اويُنَقِّرَانِهِ ( بخاری کتاب الجنائز باب ما قيل في اولاد المشرکین ) اس کے ماں باپ اسے
یہودی یا مسیحی بنا دیتے ہیں.یعنی ان کی تربیت کے اثر سے وہ بڑا ہونے سے پہلے ان کے غلط
خیالات کو قبول کر لیتا ہے اور بے سمجھے بوجھے ان کے راستہ پر چل کھڑا ہوتا ہے.اسی طرح
رسول
کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچہ کی پیدائش پر اس کے کان میں اذان کہنے کا حکم دے کر
بچپن کے اثرات کی وسعت اور اہمیت کو ظاہر کیا ہے.ملِكِ يَوْمِ الدِّین اور اِيَّاكَ نَعْبُدُ میں قرآن کریم نے ان خیالات کے غلط حصہ کی
تردید کی ہے کیونکہ جبر کی صورت میں جزا سزا ایک بے معنی فعل ہو جاتا ہے اور اياك
نَعْبُدُ کہہ کر بتایا ہے کہ انسانی ارادہ اپنی ذات میں آزاد ہے.گو ایک حد تک وہ محدود ہو لیکن
اس کے اس حد تک آزاد ہونے میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ ہدایت کو دیکھ کر اپنے لئے ایک نیا
راستہ اختیار کرلے.مثلاً گو انسان برے اثرات کے تابع ہو لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی صفات پر وہ
غور کرے تو ايَّاكَ نَعْبُدُ کی آواز اس کے اندر سے پیدا ہوسکتی ہے اور ہوتی ہے اور اس کا کوئی
انکار نہیں کر سکتا.ڈاکٹر فرائڈ اور ان کے شاگرد اس کا کیا جواب دے سکتے ہیں کہ حالات
129
Page 138
بدلتے رہتے ہیں اور خیالات بھی بدلتے رہتے ہیں.دنیا کبھی ایک حال پر قائم نہیں رہتی.اگر
بچپن کے اثرات ایسے ہی زبر دست ہوتے کہ ان سے انسان آزاد نہ ہوسکتا تو چاہئے تھا کہ
آدم سے لے کر اس وقت تک دنیا ایک ہی راہ پر گامزن رہتی.لیکن اس میں بار با تغیر ہوا ہے
اور ہورہا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسے تغیرات ممکن ہیں جو انسان کے خیالات کی روکو اس
سمت سے بدل دیں جن پر اس کے بچپن کے تاثرات اسے چلا رہے تھے.قرآن کریم نے
اس کے نہایت زبردست دلائل دیتے ہیں.مگر اس جگہ ان کی تفصیل کا موقعہ نہیں.جبر کے عقیدہ کے بالکل مخالف ایک اور خیال بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان اپنے خیالات
میں بالکل آزاد ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں کوئی دخل نہیں دیتا.اسلام اس خیال کو
بھی رڈ کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ تم ان اثرات کو جو گرد و پیش سے انسان پر پڑ رہے ہیں بالکل
نظر انداز نہیں کر سکتے.پس ضروری ہے کہ ایک بالا ہستی جو تمام اثرات سے بالا ہے انسان کی
نگران رہے اور ایسے بداثرات جب خطر ناک صورت اختیار کر جائیں تو انسان کی مدد کر کے
ان سے اسے بچائے.اور اِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کی دعا سکھا کر اس طرف توجہ دلائی ہے اور بتایا
ہے کہ تمہارا خدا ہاتھ پر ہاتھ دھر کر نہیں بیٹھا بلکہ تمہاری مجبوریوں کو دیکھ رہا ہے.پس تم اس
سے مانگو تو وہ تم کو دے گا.کھٹکھٹاؤ تو وہ تمہارے لئے کھولے گا.قرآن کریم میں بھی ھدایة کا لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے.ایک معنی اس کے کام کی طاقتیں پیدا کر کے کام پر لگا دینے کے ہیں.مثلاً قرآن کریم میں
آتا ہے اغطى كُلّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدى (طه 51) یعنی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے اس کے
مناسب حال کچھ طاقتیں پیدا کیں پھر اسے اس کے مفوضہ کام پر لگادیا.دوسرے معنی ہدایت کے قرآن کریم سے ہدایت کی طرف بلانے کے معلوم ہوتے ہیں.مثلاً فرما يا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَبْدُونَ بِأَمْرِنَا (السجدہ (25) اور ہم نے ان میں سے امام
بنائے جو ہمارے حکم کے مطابق لوگوں کو تورات کی طرف بلاتے تھے.تیسرے معنی ہدایت کے قرآن کریم سے چلاتے لئے آنے کے ہیں.جیسے کہ جنتیوں کی
130
Page 139
نسبت آتا ہے کہ وہ کہیں گے الحمد لله الذي هد تا لهذا (اعراف 44) سب تعریف اللہ
ہی کے لئے ہے جو ہمیں جنت کی طرف چلا تالا یا اور جس نے ہمیں یہاں تک پہنچادیا.اسی طرح ہدایت کے معنی سیدھے راستہ کے ساتھ موانست پیدا کرنے کے بھی ہوتے ہیں.قرآن کریم میں ہے.وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللهِ يَهْدِ قَلْبَهُ التغابن 12) جو اللہ پر کامل ایمان لاتا
ہے.اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ہدایت سے موانست پیدا کر دیتا ہے اور اچھی باتوں سے اسے
رغبت ہو جاتی ہے.اس آیت میں راہ دکھانے کے معنی نہیں ہو سکتے کیونکہ جو ایمان لاتا ہے
اسے راہ تو پہلے ہی مل چکا.ہدایت کے معنی کامیابی کے بھی قرآن کریم میں آتے ہیں.سورہ نور میں منافقوں کا ذکر
فرماتا ہے کہ وہ کہتے تو یہ ہیں کہ انہیں جنگ کا حکم دیا جائے تو وہ ضرور اس کے لئے نکل کھڑے
ہوں گے لیکن عمل ان کا کمزور ہے.فرماتا ہے قسمیں نہ کھاؤ عملاً اطاعت کرو.کیونکہ اللہ
تمہارے اعمال سے واقف ہے.پھر فرماتا ہے اے رسول! ان سے کہہ دے کہ اللہ اور اس
کے رسول کی اطاعت کرو.پھر اگر اس حکم کے باوجود تم پھر گئے تو رسول پر اس کی ذمہ داری
ہے، تم پر تمہاری.اور یاد رکھو کہ ان تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا (نور 55) اگر تم رسول کی بات اس بارہ
میں مان لو گے تو نقصان نہ ہوگا بلکہ تم کامیاب ہو جاؤ گے اور فتح پاؤ گے.چنانچہ قرآن کریم میں
آتا ہے الَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى (سوره محمد (18) جولوگ اس ہدایت کو جو انہیں خدا تعالیٰ
کی طرف سے ملتی ہے اپنے نفس میں جذب کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اور ہدایت عطا کرتا ہے.قرآن کریم سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہدایت کسی ایک چیز کا نام نہیں بلکہ اس کے بے انتہا
مدارج ہیں.ہدایت کے ایک درجہ سے اوپر دوسرا درجہ ہے.اور جولوگ اللہ تعالیٰ کے فضلوں
کے جاذب ہو جاتے ہیں انہیں ایک درجہ کے بعد دوسرے درجہ سے روشناس کرایا جاتا ہے.اس آیت میں ایسی اعلیٰ اور مکمل دُعا سکھائی گئی ہے جس کی نظیر نہیں ملتی.یہ دعا کسی
خاص امر کے لئے نہیں ہے بلکہ ہر چھوٹی بڑی ضرورت کے متعلق ہے اور دینی اور دنیوی ہر کام
کے متعلق اس دعا سے فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے.131
Page 140
اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کی دعا میں ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے
دعا مانگتے رہیں کہ وہ ہماری اس طریق کی طرف راہنمائی کرے جواچھا اور نیک ہو اور جس پر چل
کر ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہوجائیں اور جلد سے جلد کامیاب ہوں.کیسی سادہ اور کیسی مکمل یہ دعا ہے اور پھر کیسی وسیع ہے.زندگی کا وہ کونسا مقصد ہے جس
کے متعلق ہم اس دعا کو استعمال نہیں کر سکتے.جو شخص اپنے کاموں میں ان اصول کو مدنظر رکھے گا کہ (1) میرے سب کام جائز
ذرائع سے ہوں (2) میں کسی ایک مقام پر پہنچ کر تسلی نہ پا جاؤں بلکہ غیر محدود ترقی کی خواہش
میرے دل میں رہے (3) اور میرا وقت ضائع نہ ہو بلکہ ایسے طریق سے کام کروں کہ تھوڑے
سے تھوڑے وقت میں ہر کام کو پورا کرلوں، اس کے مقاصد کی بلندی اور اس کے اعمال کی درستی
اور اس کی محنت کی باقاعدگی میں کیا شک کیا جا سکتا ہے.صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ کے الفاظ نے اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ
سے مل کر معنوں میں بہت وسعت پیدا کر دی ہے.ان الفاظ نے ایک مسلمان کا مقصود صرف یہ نہیں
قراردیا کہ وہ اپنے مقرر کردہ مقاصد کے حصول کے لئے سیدھا راستہ مانگے بلکہ یہ اصل قرار دیا
ہے
کہ وہ مقاصد عالیہ کے بارہ میں بھی اللہ تعالیٰ سے التجا کرے اور درخواست کرے کہ ہدایت کے
راستے ہی مجھے نہ دکھا اور صرف منعم علیہ گروہ میں مجھے شامل نہ کر بلکہ ہدایت کے وہ طریقے اور
تعلیمیں اور عرفان کی راہیں بھی مجھے سکھا جو منعم علیہ گروہ پر اس سے پہلے ظاہر کئے جاچکے ہیں یہ اعلیٰ
امیدیں پیدا کر کے قرآن کریم نے امت محمدیہ پر ایک بہت بڑا احسان فرمایا ہے.گو اس واضح تعلیم کی موجودگی میں اس امر کے ثبوت کے لئے کہ مسلمانوں کے لئے ہر قسم
کی ذاتی ترقیات کے راستے کھلے ہیں کسی مزید ثبوت کی ضرورت تو نہ تھی مگر چونکہ مسلمانوں میں
عام طور پر مایوسی پیدا ہوگئی ہے.ہم قرآن کریم سے دیکھتے ہیں کہ اس ہدایت طلبی کے معنے
قرآن کریم نے کیا لئے ہیں اور کیا اس دُعا کی قبولیت کا بھی کوئی وعدہ کیا ہے یا نہیں؟
سورۃ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوْعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ
132
Page 141
وَأَشَدَّ تَقبِيْتًا وَإِذَ الأَتَيْنَهُمْ مِنْ لَّدُنَا اَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا.وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُوْلَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّنِ
والصَّدِيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا (نساء 7068) (یعنی
اگر کمزور مسلمان بجائے نافرمانیوں کے حقیقی اطاعت کا نمونہ دکھائیں اور ) جو ان سے کہا جاتا
ہے اس پر عمل کریں تو اس کا نتیجہ ان کے حق میں بہت ہی اچھا نکلے.اور اس سے ان کے
ایمان مضبوط ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کی درگاہ سے انہیں بہت بڑا اجر ملے اور اللہ تعالیٰ انہیں
صراط مستقیم دکھائے اور انہیں یا درکھنا چاہئے کہ جو اللہ اور اس کے اس رسول یعنی محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے منعم علیہ لوگوں میں شامل کرتا
ہے.یعنی نبیوں میں صدیقوں میں شہیدوں میں اور صالحین میں.اور یہ لوگ بہت ہی اچھے
ساتھی ہیں.اس آیت میں مسلمانوں کے لئے جو انعامات مقدر ہیں ان کا ذکر ہے اور وہی سورۃ فاتحہ
والے الفاظ میں یعنی صراط مستقیم دکھانا اور صراط مستقیم بھی ان کا جو منعم علیہ گروہ تھا.اس منعم
علیہ گروہ کی تشریح فرمائی ہے نبی، صدیق ، شہید اور صالح.جس سے معلوم ہوا کہ امت محمدیہ کو
سورہ فاتحہ میں جن اعلیٰ انعامات کے طلب کرنے کا حکم دیا گیا ہے دینی لحاظ سے اس سے مراد
اعلیٰ روحانی مقامات ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ سب کے سب مسلمانوں کو ملیں گے.بعض لوگ اس موقعہ پر اعتراض کرتے ہیں کہ سورۃ نساء کی آیت میں مَعَ الَّذِينَ
اَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمُ ہے.یعنی وہ منعم علیہ گروہ کے ساتھ ہوں گے، نہ کہ اُن میں سے.اس
اعتراض کی کمزوری خود ہی ظاہر ہے.اگر مع کا لفظ نبیوں کے ساتھ ہوتا تب تو کہا جا سکتا تھا کہ
امت محمدیہ میں نبی نہ ہوں گے مگر ایسے لوگ ہوں گے جو نبیوں کے ساتھ رہیں گے لیکن قرآن
کریم نے مَعَ کا لفظ انْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ کے ساتھ لگایا ہے.پس اگر مع کے معنے یہ کئے
جائیں کہ جس لفظ پر مع آیا ہے وہ درجہ مسلمانوں کو نہ ملے گا بلکہ اس درجہ کی معیت ملے گی تو
پھر اس آیت کے یہ معنی بنیں گے کہ مسلمانوں میں سے کوئی بھی منعم علیہ یعنی انعام پانے والا
133
Page 142
نہیں ہو گا بلکہ صرف یہ ہوگا کہ ان کے کچھ افراد انعام پانے والوں کے ساتھ رہیں گے اور ان
معنوں کو قرآن، حدیث اور عقل سلیم رڈ کرتی ہے.اگر کہا جائے کہ مع کا لفظ در حقیقت اس تشریح کے ساتھ لگتا ہے جو أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ
کی اس آیت میں کی گئی ہے تو بھی یہ اعتراض بالبدا بہت غلط ثابت ہوتا ہے کیونکہ تشریح میں چار
گروہوں کا ذکر ہے.نبیوں، صدیقوں ، شہیدوں اور صالحوں کا.اب اگر مع کے معنے صرف
معیت کے ہیں نہ کہ گروہ میں شمولیت کے تو پھر اس تشریح کے مطابق اس آیت کے یہ معنے
ہوں گے کہ مسلمان نبی نہ ہوں گے بلکہ نبیوں کے ساتھ رہیں گے.صدیق نہ ہوں گے بلکہ
صدیقوں کے ساتھ رہیں گے.اسی طرح شہید اور صالح نہ ہوں گے بلکہ شہیدوں اور صالحوں کے
ساتھ رہیں گے.اس سے زیادہ غلط معنے اور کیا ہو سکتے ہیں.اور اس سے زیادہ رسول کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کی اور امت محمدیہ کی ہتک کیا ہوسکتی ہے کہ اس امت میں نبی تو الگ رہے،
صدیق اور شہید اور صالح بھی نہ ہوں گے.اس جگہ یہ اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں
تو آپ کے بعد نبی کس طرح آسکتا ہے؟
سواس اعتراض کا جواب بھی سورۂ نساء کی آیت میں موجود ہے کیونکہ اس آیت میں وَ مَنْ يُطِعِ
اللهَ وَالرَّسُول کے الفاظ ہیں.یعنی اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے کو
یہ انعام ملیں گے.اور یہ ظاہر ہے کہ جو مطیع ہو گا اس کا کام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام سے
الگ نہیں ہوسکتا.نہ وہ کوئی شریعت لا سکتا ہے.پس جو نبی محمد رسول اللہ کے تابع ہو گا وہ
خاتم النبیین کے خلاف نہیں بلکہ اس کے معنوں کو مکمل کرنے والا ہوگا.ایک صاحب جو اس زمانہ کے مفسر ہیں اور اپنے ترجمہ قرآن کریم کو بار بار پیش
کرنے کے عادی ہیں.انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ اگر یہ دُعا نبوت کے حصول کے
لئے ہوتی تو کم از کم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام نبوت سے کھڑا ہونے سے پہلے سکھائی
جاتی مگر قرآن کریم میں اس کا موجود ہونا بتاتا ہے کہ مقام نبوت کے ملنے کے بعد سکھائی گئی.134
Page 143
پس نبوت عطا فرمانے کے بعد اس دُعا کا سکھانا بتا تا ہے کہ حصول نبوت کے لئے یہ دعا نہیں.یہ اعتراض انتہا درجہ کا بودا اور مصنف کے قلت تدبر پر دلالت کرتا ہے.اهْدِنَا القيراط
الْمُسْتَقیم میں جو دعا سکھائی گئی ہے وہ تو ایک طبعی دعا ہے.ان الفاظ میں دعا کرنا صرف
اس لئے بابرکت ہے کہ قرآنی الفاظ مبارک ہیں اور غلطی سے پاک.ورنہ تمام حق کے متلاشی
خواہ کسی مذہب کو مانتے ہوں یا نہ مانتے ہوں جب ان کے دل میں صداقت کے پانے کی
خواہش پیدا ہوتی ہے تو وہ انہی کے ہم معنی الفاظ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں
کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا اور اپنے پیاروں کا راستہ دکھا.کیا کوئی معقول انسان بھی تسلیم
کر سکتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں نبوت سے پہلے یہ خواہش پیدا نہ ہوئی
تھی کہ خدا تعالیٰ انہیں سیدھا راستہ دکھائے اور اپنے پیاروں کی راہ پر چلائے.اس قسم کا تو
خیال بھی انسان کو کافر بنادیتا ہے.محمد رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی تڑپ ہی تو تھی جس
نے خدا تعالیٰ کے فضل کو اپنی طرف جذب کیا.اس تڑپ کو ہی اهْدِنَا الصِّرَاط
الْمُسْتَقِیم کے الفاظ میں بیان کیا گیا ہے.قرآنی الفاظ نے صرف یہ فرق پیدا کیا ہے کہ
اول الفاظ ایسے چنے ہیں جو کامل ہیں اور ہر نقص سے پاک ہیں.دوسرے ان کے ذریعہ سے
ان کے دل میں بھی تڑپ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے جن کے دل میں یوں تڑپ نہ
ہوتی.تیسرے امید پیدا کر دی گئی ہے کہ ایسی دعا کرو گے تو قبول ہوگی.بلکہ حکم دیا ہے کہ یہ دعا
کرو.ورنہ یہ خیال کرنا کہ اس
قسم کا مفہوم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں پیدا نہیں ہوتا
تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت ہتک ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی بھی ہتک ہے کہ محمد
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تو سیدھا راستہ پانے کی کوئی تڑپ نہ تھی مگر اللہ تعالیٰ نے
زبر دستی آپ کو نبی بنا دیا.(نعوذ بالله من ذلك الخرافات)
پھر اگر یہ اعتراض معقول ہے تو کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن
کریم کے نزول سے پہلے نیک تھے یا نہیں.خدا تعالیٰ کی محبت میں سرشار تھے یا نہیں.135
Page 144
خدا تعالیٰ کا قرب انہیں قرآن کریم کے نزول سے پہلے حاصل تھا یا نہیں.اگر ان باتوں کے جواب اثبات میں ہیں تو کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ پھر ہمیں اس نماز کی کیا
ضرورت ہے جو قرآن کریم میں مذکور ہے.اس قسم کے روزہ کی کیا ضرورت ہے جو قرآن کریم
میں مذکور ہے.اس قسم کے جہاد کی کیا ضرورت ہے یا اور دوسرے شرعی احکام کی کیا ضرورت
ہے جو قرآن کریم میں مذکور ہیں.جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تقویٰ اور محبت الہی بغیر
ان احکام پر عمل کرنے کے حاصل ہو گیا تھا تو ہمیں بھی ان کے بغیر حاصل ہو جائے گا.بلکہ
دین کے معاملات کو جانے دو.دنیوی چیزوں میں ہی اگر کوئی کہے کہ پہلی مرغی یا پہلا انڈا
کیونکر بنا تھا.پہلا دانہ اور پہلا درخت کیونکر بنا تھا.اب بھی اسی طرح بن جائے گا.ہمیں ان
کے پیدا کرنے کے لئے قانون قدرت کے مطابق کوشش کرنے کی کیا ضرورت ہے.تو
اس شخص کو ہر کوئی نادان کہے گا.خدا تعالیٰ کا قانون اس وقت کے لئے جب بیچ مٹ جاتا ہے
اور ہے اور جب بیج پیدا کر دیا جاتا ہے اور ہے.محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم
کے نزول سے پہلے دنیا سے پاکیزہ تعلیم مٹ چکی تھی.محمد رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک
فطرت میں جذبات محبت پیدا ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے بغیر اس کے کہ وہ خاص الفاظ یا خاص
انداز میں بیان کئے جاتے ان کو قبول کیا اور نوازا.لیکن جب قرآن کریم نازل ہو گیا.ہراک
امر کے لئے خاص قواعد بن گئے تو اب ان کے بغیر وہ نعمتیں حاصل نہیں ہوسکتیں جو اس سے پہلے
حاصل ہوسکتی تھیں.محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اور شریعت کی بنیا درکھ دی اور اب
اس قانون اور شریعت سے باہر رہنے والا ہر گز کامیاب نہیں ہوسکتا.اس سوال پر ایک اور پہلو سے بھی نظر کی جاسکتی ہے اور وہ یہ کہ کیا نبی صرف ایک عہدہ کا
نام ہے یا نبی کے لئے تقویٰ طہارت اور قرب الی اللہ کی بھی شرط ہے؟ اگر ان باتوں
کا پایا جانا
نبی کے لئے شرط ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ کیا یہ ہوسکتا ہے کہ غیر نبی ، نبی سے تقویٰ اور طہارت
اور قرب الی اللہ میں زیادہ ہو؟
136
Page 145
اگر تو اس کا جواب یہ مفسر اور ان کے ہمنوا یہ دیں کہ ہاں یہ ممکن ہے کہ ایک غیر نبی تقویٰ
طہارت اور قرب الی اللہ میں نبی سے بڑھ کر ہو تو پھر نزاع لفظی رہ جاتی ہے.لیکن اگر اس سوال کا جواب یہ ہو کہ غیر نبی ، نبی سے ان باتوں میں افضل نہیں ہوسکتا تو جو
شخص یہ کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ظلی بروزی اور نبوت محمدیہ کی تابع
نبوت بھی نہیں ہوسکتی وہ یہ کہتا ہے کہ اس امت میں کوئی شخص قرب الی اللہ کے اس مقام کو
نہیں پہنچ سکتا جس مقام پر پہلے لوگ پہنچے تھے اور ایسا دعویٰ کرنے والا
شخص یقیناً امت محمدیہ کو
انعام سے محروم قرار دیتا ہے.مثلا ایک اعتراض انہی مفسر صاحب نے یہ کیا ہے کہ پھر کیا وجہ ہے کہ گزشتہ تیرہ سوسال
میں ایک مسلمان کی بھی دعا اس بارہ میں قبول نہ ہوئی ؟
اس کا جواب یہ ہے کہ دعا کی قبولیت تو دعا کی مقدار اور نوعیت پر منحصر ہے.یہ معترض صاحب
بھی تسلیم کرتے ہیں کہ صدیقیت کا مقام اس اُمت میں مل سکتا ہے.پس یہی سوال ان کے
مسلمات کے متعلق بھی کیا جا سکتا ہے کہ اس امت میں کتنے لوگوں کو صد یقیت کا مقام ملا ہے.اگر گزشتہ تیرہ سوسال میں صرف ابوبکر کو ملا ہے تو یہی اعتراض پھر بھی پڑے گا کہ کیا تیرہ سو سال میں
یہ دعا اور کسی کے حق میں قبول ہی نہ ہوئی.اور اگر اوروں کو بھی ملا ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ کیا وہ
اشخاص عمر اور عثمان اور علی سے بڑھ کر تھے یا کم.اگر کم تھے تو پھر یہ کیونکر ہوا کہ کم درجہ کے لوگ
رض
رض
صدیق بن گئے اور بڑے درجہ کے لوگ شہید تک ترقی پا سکے.صدیق نہ کہلا سکے.غرض جو اعتراض نبوت کے اجرا پر ہوتا ہے وہی اعتراض صد یقیت کا دروازہ کھلا تسلیم کر
کے اس پر ہوتا ہے.پس یہ اعتراض محض قلت تدبر کی وجہ سے ہے حقیقت پر مبنی نہیں.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ فاتحہ کو اُم القرآن اور ام الکتاب بھی فرمایا ہے
اور قرآن عظیم بھی فرمایا ہے گویا ایک طرف اسے ذریعہ پیدائش قرار دیا دوسری طرف اسے وہ
چیز بھی قرار دیا جو اس سے پیدا ہوئی ہے.اس میں ایک زبر دست روحانی نکتہ نکلتا ہے اور وہ یہ
137
Page 146
ہے کہ روحانی دنیا میں پہلی حالت دوسری حالت کی پیدا کرنے والی ہوتی ہے.اس لئے پہلی
حالت ایک جہت سے ماں کہلاتی ہے اور بعد کی حالت اولاد کہلاتی ہے.اسی نسبت سے سورۃ
فاتحہ کو اُم القرآن بھی کہا گیا اور بوجہ اس کے کہ وہ خود قرآن بھی ہے اسے قرآن بھی کہا گیا.انسانوں کے متعلق بھی ایسے ہی تغیرات کے مواقع پر اس قسم کے تشبیہی الفاظ استعمال کر لئے
جاتے ہیں.چنانچہ سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومنوں کی مثال امرأَة فرعون اور
مريم بنت عمران سے دی جاسکتی ہے اور جن مومنوں کی مثال مریم بنت عمران سے دی
ہے ان کے متعلق آخر میں فرمایا ہے فَنَفَخْنَا فِیهِ مِنْ رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَتِ
رَبَّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَنِتِينَ (سوره تحریم (13) ہم نے اس کے اندر اپنا
کلام پھونکا اور وہ اپنے رب کے کلام پر اور اس کی کتابوں پر ایمان لائی اور آخر وہ ایک
فرمانبردار مرد کی طرح ہو گئی.یعنی جو لوگ مریمی صفت ہوتے ہیں جب ترقی کرتے
کرتے کلام الہی کے مورد ہو جاتے ہیں تو مسیحی نفس بن جاتے ہیں.غرض سورہ فاتحہ کا نام اتم القرآن اور ام الکتاب بھی رکھنا اور اسے قرآن عظیم بھی کہنا
اسلامی اصطلاحات پر ایک لطیف روشنی ڈالتا ہے اور ان لوگوں کے لئے اس میں ہدایت ہے جو
اس مسئلہ کو نہیں سمجھ سکے کہ امت محمدیہ کے ایک شخص کا نام کس طرح مریم بھی رکھا گیا اور عیسی
بھی.اگر سورہ فاتحہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی اتم بھی فرماتے ہیں اور قرآن
بھی.تو ایک سچے مسلمان کے لئے اس امر کا سمجھنا کیا مشکل ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک شخص کو مریم
بھی فرماتا ہے اور عیسی بھی.اس کی وہ حالت جب وہ خدا کے سامنے اس زمانہ میں ایک مسیح
کے ظہور کے لیے چلا رہی تھی مریمی حالت تھی اور اس کی وجہ سے وہ مریم کہلایا.جس طرح سورۃ
فاتحه اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیم کی دعا کی وجہ سے جو ایک ہدایت نامہ کے لئے پکار
رہی تھی اُم القرآن اور ام الکتاب کہلائی.لیکن جب اس فرد کامل کی دعاسنی گئی اور خدا تعالیٰ نے
اسی کو دنیا کے لئے مسیحی نفس عطا کر کے مبعوث فرما دیا تو وہ عیسی کہلایا.جس طرح اهْدِنَا
الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کی پکار نے بلند ہو کر جب قرآن کریم کو دنیا کی طرف کھینچا اور یہ دُعا
138
Page 147
خود اس کا حصہ بن گئی تو ائم القرآن اور ام الکتاب کہلانے کے بعد وہ قرآن عظیم کہلانے لگی.اس دعا کے بارہ میں ایک اور نکتہ بھی یادرکھنے کے قابل ہے جسے صحابہ نے مدنظر رکھا
اور ایک ایسا اعلیٰ درجہ کا نمونہ دنیا کے سامنے پیش کیا جس کی مثال دنیا کی کسی اور قوم میں نہیں مل
سکتی اور اگر بعد کے مسلمان بھی اسے یادر کھتے تو یقیناً وہ بھی ایسا اعلیٰ درجہ کا نمونہ دکھاتے کہ دنیا
کی تاریخ میں ان کا نام ہمیشہ کے لئے یاد گار رہ جاتا.مگر افسوس کہ مسلمانوں نے اس زرین
ہدایت کو جو اس آیت میں بیان کی گئی تھی بھلا دیا اور اس معیار سے گر گئے جس پر کہ اللہ تعالیٰ
انہیں کھڑا کرنا چاہتا تھا.اگر آج بھی مسلمان اس ہدایت کو اپنا مطمح نظر بنالیں تو سب تکلیفیں ان
کی فور اڈور ہوسکتی ہیں اور پھر وہ بے مثال عزبات اور رفعت حاصل کر سکتے ہیں.وہ سبق جو اس آیت میں بیان ہوا ہے یہ ہے کہ ہر قوم کا ایک مقصد ہوتا ہے اور وہ اس مقصد
کے حصول کے لئے جد و جہد کرتی ہے.اسی طرح دُنیا کی پیدائش کا بھی ایک مقصد ہے.جو قوم
اس مقصد کو پورا کر دے دُنیا کی پیدائش کا اصل مقصود کہلانے کی وہی قوم مستحق ہو گی.آدم
علیہ السلام دنیا میں آئے اور کچھ نیکیاں انہوں نے دنیا کو بتائیں.اس زمانہ کے لوگوں کے
لئے وہ نہایت اعلی تعلیم پر مشتمل تھیں.ان نیکیوں پر عمل کر کے اس زمانہ کے لوگوں نے بہت
بڑی روحانی اور اخلاقی تبدیلی پیدا کی اور ان کی ذہنی قوتیں پہلے لوگوں سے بہت آگے نکل
گئیں.مگر ابھی انسان اس کمال کو نہ پہنچا تھا جس کے لئے اسے پیدا کیا گیا تھا.پس اس کی
ترقی کے لئے جستجو جاری رہی یہاں تک کہ نوح علیہ السلام پیدا ہوئے اور وہ انسان کو ترقی کی
بلندی پر ایک منزل اور اونچالے گئے.مگر انسان نے گونوح علیہ السلام کے ذریعہ سے روحانی
اور اخلاقی اور ذہنی طور پر ترقی کی مگر ابھی وہ مقصد حاصل نہ ہوا تھا جس کے لئے انسان کو پیدا کیا
گیا تھا.چنانچہ آپ کے بعد اور نبی آیا اور اس کے بعد اور.اور اس کے بعد اور.اور یہ سلسلہ
چلتا چلا گیا یہاں تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ظاہر ہوئی اور آپ نے تمام
راز ہائے سربستہ جو انسان پر اب تک پوشیدہ تھے ظاہر کر دئیے اور دینی اور ذہنی اور اخلاقی ترقی
کے لئے جس قدر ضروری امور تھے وہ سب کے سب بیان کر دئیے اور گویا علمی طور پر مذہب کو
139
Page 148
کمال تک پہنچا دیا.اور الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي كا
اعلان کر دیا.مگر جب تک اس اعلی تعلیم کو جامہ عمل نہ پہنایا جاتا اس کے نزول کی غرض پوری نہ
ہوسکتی تھی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پوری طرح کامیاب نہیں کہلا سکتی تھی.پس
اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ میں مسلمانوں کو اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ
صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ کی دعا سکھائی اور کہا کہ ہمیشہ اپنے سامنے یہ مقصد رکھو کہ
جس مقام
محمود کو سامنے رکھ کر اس دُنیا نے شروع سے رُوحانی سفر اختیار کیا ہے اور جس کی
مختلف منزلوں تک مختلف انبیاء انسانوں کو پہنچاتے چلے آئے ہیں اور جس کی آخری منزل
تک پہنچانا محمد رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپر د ہوا ہے اس تک تم پہنچ جاؤ.پس سارے کے سارے منعم علیہ گروہ کی نعمتوں سے ہمیں حصہ دئے کے یہ معنی ہیں کہ اے
خدا ہم کو آدم کی امت کی نیکیاں دے.اور پھر ہماری ذہنی ترقی نوح کی امت کی طرح کر.پھر
ابراہیم کی امت کے مقام پر پہنچا.اور پھر موسیٰ کی اُمت کے کمالات ہمیں دے.اور پھر مسیح کی
روحانیت کے اثر سے ہمیں حصہ دے.اور اس طرح منزل به منزل روحانی بلندیوں پر
چڑھاتے ہوئے بالآخر مقام محمد پر ہم کو قائم کر دے تا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے
مقصد میں کامیابی حاصل ہو اور وہ مقام محمود پر فائز ہو جائیں.غرض صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ سے مُراد انسانی کمال کی وہ آخری منزل ہے
جس کی طرف شروع سے انسانی قافلہ بڑھتا آ رہا ہے اور جس کی مختلف منزلوں کی راہنمائی
مختلف زمانہ کے انبیاء کے سپرد تھی اور جس کی آخری منزل تک پہنچانا محمد رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کے سپرد ہوا تھا.اور اس دعا کے ذریعہ سے اُمت محمدیہ کے افراد درخواست کرتے
ہیں کہ الہی دین کی تکمیل تو محمد رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے تو نے کر ہی دی ہے.اب یہ امر باقی ہے کہ ہم لوگوں کے اعمال بھی اس دین کے مطابق ہو جائیں اور ہم ان تمام مخفی
اور اعلیٰ قوتوں کا اظہار کریں جن کی مختلف انبیاء کے ذریعے سے نشوونما کی جاچکی ہے اور جن کا
پیدا کرنا انسانی پیدائش کا آخری اور اعلیٰ مقصد ہے.سو اس کام کے لئے ہم کھڑے ہو گئے ہیں.140
Page 149
اب تو ہماری مدد کر اور ان سب منازل عرفان کو یکجائی طور پر طے کرا دے جنہیں فرڈ مختلف
انبیاء کے ذریعہ سے مختلف اقوام طے کر چکی ہیں تا کہ انسانی پیدائش کا مقصد امت محمدیہ کے
ذریعہ سے پورا ہو جائے.صحابہ نے اس مقصد کو سامنے رکھا اور زمانہ سابق کی سب اقوام کے اخلاق کو یکجائی طور پر
اپنے وجود میں پیدا کر کے ایک بے مثال نمونہ دنیا کے سامنے پیش کیا.آج اگر ہماری جماعت
اس مقصد کو پھر اپنے سامنے رکھ لے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام محمود پر مبعوث ہونے
کا وقت اور بھی قریب ہو جائے گا اور دنیا اپنی پریشان کن بے تابیوں سے محفوظ ہو جائے گی.ہر شخص یا قوم جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے اس کے غضب کو بھڑ کا چکی ہو مَغْضُوبِ
عَلَيْهِمْ میں شامل ہے.اسی طرح ہر قوم جو غیر اللہ کی محبت میں کھوئی گئی ہو اور اللہ تعالیٰ کو بھلا
بیٹھی ہو وہ ضال ہے.لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں لفظوں کے خاص معنے بھی
کئے ہیں.امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں عدی بن حاتم سے ایک لمبی روایت نقل کرتے ہیں
جس کے آخر میں ہے.قال ( یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) إِنَّ الْمَغْضُوبَ عَلَيْهِم
الْيَهُودُ وَاِنَّ الظَّالِينَ النَّصَارى مغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں اور ضالین سے مراد
نصاری ہیں.اسی طرح ترمذی نے بھی یہی روایت نقل کی ہے اور اس کے بارہ میں کہا ہے کہ
حسن غریب ہے.ابن مردویہ نے ابوذرغفاری سے ایک روایت نقل کی ہے کہ سألت
رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ قَالَ الْيَهُودُ وَ قُلْتُ
الضَّالِّينَ قَالَ النَّصارى (بحواله فتح البیان جلد اول) یعنی حضرت ابوذر فرماتے
ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا مغضوب علیہم کون ہیں ؟ آپ نے فرمایا:
یہود.پھر میں نے کہا کہ ضالین کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا: نصاری.بہت سے صحابہ سے بھی یہ معنے ثابت ہیں.مثلاً ابن عباس اور عبد اللہ بن مسعود.ابن ابی
حاتم تو یہاں تک کہتے ہیں وَلَا أَعْلَمُ بَيْنَ الْمُفْسِرِينَ فِي هَذَا اخْتِلَافًا یعنی تمام مفسرين
ان معنوں پر متفق ہیں اور اس بارہ میں میں نے ان میں کوئی اختلاف نہیں دیکھا (ابن کثیر ).141
Page 150
قرآنی آیات سے بھی ان معنوں پر استدلال ہو سکتا ہے کیونکہ یہود کی نسبت قرآن کریم میں
بار بار غضب کا لفظ استعمال ہوا ہے.مثلاً سورہ بقرہ میں ہی فرماتا ہے.فَبَاؤُوُا بِغَضَبٍ عَلَى
غَضَبِ (البقرة (91) یہود خدا کے متواتر غضب کو لے کر اس طرح بن گئے کہ گویا خدا تعالیٰ کا
غضب انہی کے لئے ہے.اس کے برخلاف نصاری کے لئے ضل کا لفظ آیا ہے جیسے فرماتا
ہے الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَوةِ الدُّنْيَا ( کهف 105) اسی طرح سورۃ مائدہ میں
مسیحیوں کا ذکر کر کے اور مسیح اور ان کی والدہ کو خدائی کا رتبہ دینے کا بیان کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا
ہے یا هَلَ الْكِتَبِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَلْ
ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيل (مائده 78) اے اہلِ
کتاب ( یعنی نصاری کیونکہ اس جگہ انہی کا ذکر ہے ) اپنے مذہبی خیالات میں غلو سے کام نہ لو
اور ایسے لوگوں کے خیالات اور ان کی خواہشات کے پیچھے نہ چلو جو پہلے سے گمراہ چلے آ رہے ہیں
اور بہتوں کو گمراہ کر چکے ہیں اور سیدھے راستہ سے بھٹک چکے ہیں.یعنی عام نصاری کو بتایا ہے
کہ سب نصاری شرک کے عقیدہ کے قائل نہ تھے.ان میں سے موحد بھی تھے اور مشرک بھی.مشرک گروہ جو مسیح کو خدا قرار دیتا تھا وہ خود بھی گمراہ تھا اور اس نے باقی مسیحیوں میں بھی اپنا
عقیدہ پھیلانا شروع کیا اور اکثر حصہ کو اس گمراہی کے عقیدہ پر لے آیا.اور جو سیدھا راستہ توحید
کا تھا اُسے چھوڑ دیا.غرض قرآن کریم سے بھی اور اقوال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ
مغضوب علیہم میں خاص طور پر یہود مراد ہیں اور ضالین سے خاص طور پر نصاریٰ مراد ہیں.یہ آیت الَّذِينَ کا یا أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمُ میں جو ھم کی ضمیر ہے اس کا بدل ہے.اور
اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے اللہ ہمیں منعم علیہ گروہ کے راستہ پر چلا اور منعم علیہ سے ہماری مراد
ایسے منعم علیہ ہیں جو بعد میں تیرے غضب کے مورد نہ ہو گئے ہوں یا جو کسی اور کی محبت میں تجھے
چھوڑ نہ بیٹھے ہوں.اس مضمون میں مومن کے لئے خشیت کا بہت بڑا سامان مہیا ہے.اسے یادرکھنا چاہئے کہ جب
142
Page 151
تک انسان اس مقام تک نہ پہنچ جائے جس کے بعد کوئی گمراہی نہیں اسے کبھی مطمئن نہیں ہونا
چاہئے اور جدو جہد میں لگا رہنا چاہئے کہ اس کا قدم زیادہ سے زیادہ مضبوطی کے ساتھ تقویٰ کی
راہوں پر پڑتا رہے تا ایسانہ ہو کہ تھوڑی سی غفلت سے وہ اپنے مقام سے گر کر تباہ اور برباد ہو جائے.اس آیت میں ایک بہت بڑی پیشگوئی ہے جو ہر سوچنے والے کے لئے ترقی ایمان کا
موجب ہوسکتی ہے اور وہ یہ ہے کہ جس وقت یہ سورۃ نازل ہوئی ہے اس وقت یہود اور نصاریٰ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہ تھے بلکہ کفار مکہ آپ کے مقابلہ پر تھے.یہود اور
نصاری کی تعداد مکہ میں آٹے میں نمک کے برابر بھی نہ تھی اور نہ ان کا حکومت میں کوئی دخل
تھا.پھر کیا وجہ ہے کہ اس سورۃ میں یہ نہیں سکھایا گیا کہ دعا مانگو کہ اللہ تعالی تم کو پھر مشرک
ہونے سے بچائے بلکہ یہ سکھایا گیا ہے کہ دُعا کرو کہ اللہ تعالیٰ یہود اور نصاریٰ کے طریق پر چلنے
سے بچائے.مشرکین کا ذکر چھوڑ کر یہ پیشگوئی کی گئی تھی کہ مشرکین مکہ کا مذہب ہمیشہ کے لیے
تباہ ہو جائے گا اس لئے اس دعا کی ضرورت ہی نہیں کہ خدا مسلمانوں کو مشرکین مکہ سا ہونے
سے بچائے.لیکن یہود اور نصاریٰ کا مذہب قائم رہے گا اس لئے اس بارہ میں دعا کرنے کی
ضرورت رہے گی کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہود و نصاریٰ میں شامل ہونے سے بچائے.اس آیت میں یہ امر بھی قابل غور ہے کہ مسیحی تو اپنے مذہب میں مسلمانوں کو شامل
کرتے ہیں اس لئے اس دُعا کی ضرورت معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو نصاریٰ کے
فتنہ سے بچائے.لیکن یہود تو بالعموم غیر مذاہب کے افراد کو اپنے اندر شامل نہیں کرتے پھر اس
دعا کی کیا ضرورت ہے کہ خدا تعالیٰ انہیں یہود ہونے سے بچائے.خدا تعالیٰ کا کلام ایک
بے معنی اور بے ضرورت دعا کے کرانے کا مجرم نہیں ہو سکتا.نہ یہ سمجھ میں آسکتا ہے کہ محمد رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایسی غیر ضروری دعا دن میں تیس چالیس بار پڑھنے کا
حکم دیں گے.پس مسلمانوں کو غور کرنا چاہئے کہ یہودی فتنہ کسی اور رنگ میں تو ان کے لئے
ظاہر نہیں ہونے والا.کیا یہ تو ممکن نہیں کہ آنے والے مسیح کا انکار کرنے کی وجہ سے مسلمانوں
کی حالت یہود کے مشابہ ہو جائے گی.اور یہ حالت اس وقت ہوگی جبکہ مسیحی فتنہ بھی بڑے زور
143
Page 152
سے اسلام پر حملہ کر رہا ہوگا.پس ایک طرف تو ایک مثیل مسیح کا انکار کر کے انہیں یہود سے
مشابہت ہو جائے گی اور وہ خدا تعالیٰ کی نصرت سے محروم ہو جائیں گے دوسری طرف مسیحیت
ان پر حملے کر کے ان کے ہزاروں جگر کے ٹکڑے ان سے چھین کر لے جائے گی.کیا یہ آیت
ایک زبر دست پیشگوئی نہیں ہے؟ کیا اس سے فائدہ اٹھا کر وہ ان دو آگوں سے نجات حاصل
نہیں کر سکتے؟
اس سورۃ پر نظر غائر ڈالنے سے ایک اور لطیف خوبی کا پتہ چلتا ہے جو خدا تعالیٰ نے اس
سورۃ کی آیات میں رکھی ہے.اور وہ یہ ہے کہ صفات الہیہ اور دعاؤں کا بیان بالکل ایک
دوسرے کے مقابل میں ہوا ہے چنانچہ الحمد لله ( یعنی سب تعریف اللہ کے لئے ہے )
کے مقابلہ میں اِيَّاكَ نَعْبُدُ ) ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں) ہے.جس سے بتایا ہے کہ
جونہی انسان معلوم کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب خوبیوں کا جامع ہے تو وہ بے اختیار کہہ اٹھتا ہے
کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں.پھر ربّ الْعَلَمِينَ کے مقابلہ میں اِيَّاكَ
نَسْتَعِينُ کو رکھا ہے کیونکہ جب انسان کو یقین ہو جائے کہ ہمارا خدا ہر ایک ذرہ ذرہ کا خالق
اور محسن ہے تو وہ کہ اُٹھتا ہے کہ ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں.اسی طرح آل محمن کے مقابلہ
میں جس کے معنی بغیر محنت اور مبادلہ کے دینے والا اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيم کو رکھا
ہے.کیونکہ جب انسان دیکھتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے انسان کے کسی عمل کے بغیر اس کی تمام
ضروریات کو پورا کیا ہے تو وہ بے اختیار کہہ اٹھتا ہے کہ میری سب سے بڑی ضرورت تو حضور
تک پہنچنا ہے.اس کے پورا کرنے کے سامان بھی پیدا کیجئے.پھر الرَّحِیم ( یعنی محنت کا
عمدہ بدلہ دینے والا) کے مقابلہ میں صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ رکھا.یعنی ایسے لوگوں کا
رستہ دکھائیے جن پر آپ نے انعام کئے ہیں.سیدھے راستہ پر چلاتے چلاتے مجھے ان
انعامات کا وارث کر دیجئے جو پہلے لوگوں کو ملے ہیں.کیونکہ رحیمیت چاہتی ہے کہ کسی کام کو
ضائع نہ ہونے دیا جائے.پھر ملِكِ يَوْمِ الدِّین کے مقابلہ میں غَيْرِ الْمَغْضُوبِ
144
Page 153
عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالین کو رکھا کیونکہ جب انسان کو یقین ہو کہ میرے اعمال کا حساب لیا
جائے گا تو فوراً اس کے دل میں ناکامی کا خوف بھی پیدا ہو جاتا ہے.پس بندہ ملِكِ يَوْمِ
الدین پر غور کر کے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنے کی دُعا کرتا ہے.صحیح حدیث میں آتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں جب سورۃ فاتحہ کو
غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّين پر ختم کرتے تو آمین کہتے جس کے معنے اللهُم
اسْتَجِبْ لَنا کے ہیں.یعنی اے اللہ ! ہماری یہ عرض قبول فرما.اور باتباع ارشاد نبوی صحابہ
رضی اللہ عنہم کا یہی عمل ثابت ہے.(ماخوذ از تفسیر کبیر حضرت خلیفة المسیح الثانی)
حضرت خلیفہ امسیح الرابع رحمہ اللہ فرماتے ہیں :
کلیڈو سکوپ (Kaleidoscope) بچوں کی ایک کھیل کا نام ہے.جو ایک
تکون ٹیوب کی شکل میں ہوتی ہے.اس کے ایک طرف عدسی شیشہ ہوتا ہے اور دوسری طرف
عکسی.اور اس کے اندر کچھ مختلف رنگ کے شیشوں کے ٹکڑے پڑے ہوتے ہیں.جب بچہ
اس عدسی شیشہ سے اس ٹیوب کے اندر دیکھتا ہے تو شیشہ کے مختلف ٹکڑے عکسی شیشہ سے منعکس
ہو کر خاص شکل میں منظم دکھائی دیتے ہیں.اور جب وہ اس کا ذرا سا رخ پلٹ دے تو اچانک
وہ ٹکڑے ایک نئی منظم شکل میں نظر آنے لگتے ہیں.پھر وہ ان کو تھوڑی سی اور حرکت دیتا ہے تو
ان کا رخ اچانک بدلتا ہے اور وہ ایک نئی تنظیم کی شکل میں نظر آنے لگ جاتے ہیں.یکھیل
مختلف زاویوں سے تصویریں بچوں کے سامنے پیش کرتا ہے.لیکن وہ زاویے بھی محدود ہیں اور
تصویریں بھی محدود.اللہ تعالیٰ نے مومن بندوں کے لئے ایک روحانی کلیڈ وسکوپ بھی بنا رکھی ہے.جس کے نہ
زاویے محدود ہیں ، نہ وہ نظارے محدود ہیں جو اس کلیڈ وسکوپ سے نظر آتے ہیں.اور وہ کلیڈ و
سکوپ سورۃ فاتحہ ہے.مختلف زاویوں سے جب آپ سورۃ فاتحہ کے رخ بدلتے ہیں اور مختلف
145
Page 154
جہتوں سے اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو حیرت انگیز حسین نظارے دکھائی دیتے ہیں جو لا متناہی
ہیں.ان کی کوئی حدوبست نہیں.آج امت کو چودہ سو سال ہو چکے ہیں جب یہ سورۃ نازل ہوئی تھی بلکہ چودہ سو سال سے بھی
کچھ زائد سال گذر چکے ہیں.اس عرصہ میں بے شمار علماء ربانی نے اس پر قلم اٹھایا.وہ اس کے
نظاروں سے خود بھی محفوظ ہوئے اور دنیا کو بھی ان نظاروں میں شریک کیا.لیکن یہ خزانہ ختم
ہونے میں نہیں آتا.کیونکہ جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے یہ نظارے لامتناہی ہیں.اس سورۃ کے آخر پر ایک دعا سکھائی گئی ہے.اھدِنَا القِرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ
الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمُ وَلَا الضَّالِّينَ.کہ اے خدا ہمیں
سیدھے راستہ کی ہدایت دے وہ راستہ جس پر انعام پانے والے چلے تھے یا جس پر چل کر انعام
ملتے ہیں.ایسا راستہ نہ ہو جس راستہ پر غضب نازل ہوتا ہے یا کج فطرت لوگ دکھائی دیتے
ہیں.گمراہ لوگ دکھائی دیتے ہیں.ایسا راستہ ہم نہیں مانگتے.میں نے سوچا کہ ہم جب سیدھا راستہ مانگتے ہیں تو سیدھے راستہ پر تو انعام والے ہی ملنے
چاہئیں.یہ مغضوب کا ذکر بیچ میں کہاں سے آگیا؟ اور ضالین سے بچنے کی دعا کیوں سکھائی
گئی ؟ اُس وقت اللہ تعالیٰ نے میری توجہ اس مضمون کی طرف پھیری کہ صراط مستقیم در اصل وہ
راستہ ہے جو خدا تعالیٰ کی ہر مخلوق کو بالآخر اس تک پہنچائے گا.اور اس کی دو شکلیں ظاہر ہوتی
ہیں.ایک صراط مستقیم ہے جو منعم علیہ گروہ کا راستہ ہے اور دوسری وہ راہ ہے جس پر خدا کے وہ
بندے چلتے ہیں جو مغضوب ہو جاتے ہیں یا گمراہ ہو جاتے ہیں اور ضالین کے زمرہ میں شمار
کئے جاتے ہیں.چنانچہ اس مضمون پر غور کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے میری نگاہ صراط مستقیم کی شکل میں پہلی
آیات کی طرف مبذول فرما دی.در اصل الحمدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ میں جس راستہ کا ذکر
فرمایا گیا ہے، یہ حد کا رستہ ہے جو ملِكِ يَوْمِ الدِّین پر ختم ہوتا ہے.وہی صراط مستقیم ہے اور
146
Page 155
صراط مستقیم کے دونوں پہلو اس آیت میں بیان فرما دئیے گئے ہیں.جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے مخلوق کی ہر شکل بالآخر اپنے رب تک اس طرح پہنچتی ہے کہ
وہ اس پر ملِكِ يَوْمِ الدِین کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے.مُلِكِ يَوْمِ الدِّينِ سے کیا مراد
ہے.قرآن کریم دوسری جگہ اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے :يوم
لا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذ لله.(الانفطار 40) یعنی کوئی نفس نہ
کسی دوسرے نفس کا مالک ہوگا نہ اپنے نفس کا اور ہر قسم کی مالکیت اور اختیار خالصہ اللہ کا ہو
گا.گویا اس جہان میں جو ہم عارضی مالک بنائے گئے تھے خواہ اشیاء کے مالک ہوں یا صفات
کے، اس عارضی مالکیت سے ہر وجود کلیۂ عاری ہو چکا ہوگا.نہ اس کی ذاتی صفات ہوں گی.نہ
مالکیت کی دوسری شکلوں پر اسے کوئی اقتدار ہوگا اور کلیۂ نیست ہو کر اپنے رب کے حضور لوٹے
گا.اسے کسی چیز پر بھی اختیار اور قبضہ نہیں رہے گا.یعنی انجام کار صرف خدا ہی مالک ہوگا.ہر
چیز اس کی طرف لوٹ چکی ہوگی اور ہر مخلوق ہر دوسری چیز سے عاری ہو چکی ہوگی.یہ جو مضمون ہے جیسا کہ میں نے بیان کیا ، یتخلیق کی ہر شکل پر حاوی ہے.انسان بھی اس
کے دائرہ میں ہے.حیوان بھی اس کے دائرہ میں ہے.نباتات بھی اس کے دائرہ میں ہیں اور
جمادات بھی اس کے دائرہ میں ہیں.اور ہر چیز اس حالت میں اپنے رب کی طرف لوٹتی ہے کہ
ذاتی طور پر اس کا کچھ بھی باقی نہیں رہتا.آج کی سائنس نے مادہ کے اپنے رب کی طرف
لوٹنے کا جو نقشہ کھینچا ہے اس میں بھی بعینہ ملِكِ يَوْمِ الدِّينِ کی تفسیر نظر آتی ہے.چنانچہ
سائنسدان آسمانوں کے اجسام پر غور کرتے ہوئے اس نتیجہ پر پہنچے کہ بہت سے بڑے بڑے
ستارے جو ہمارے سورج سے سینکٹروں گنا بڑے ہیں اچانک کہیں غائب ہوتے ہوئے
دکھائی دیتے ہیں.اور اتنی شدید قوت کا ایک مرکز اُن کو اپنی طرف کھینچتا ہے کہ ان کا کچھ بھی باقی
نہیں رہتا.وہ اس مرکز میں ڈوب جاتے ہیں اور پھر اُن کی کوئی خبر نہیں ملتی.یہ تو آج کی دنیا میں ایک عام بات ہو چکی ہے.یہ کوئی نئی خبر نہیں رہی لیکن جس طرف میں
147
Page 156
توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ سائنسدانوں کی یہ تحقیق ہے کہ آخر وہ کیا بن جاتے ہیں اور کہاں چلے
جاتے ہیں.اس آخری صورت کے متعلق سائنسدان صرف اتنا ہی بتا سکتے ہیں کہ وہ ہمارے
ادراک کی حد سے باہر نکل جاتے ہیں اور یہ کہنے کے باوجود خود بھی نہیں سمجھ سکتے کہ یہ حالت ہے
کیا چیز ؟ وہ کہتے ہیں کہ جب بھی یہ ستارے غائب ہوتے ہیں تو ایک ایسے ستارے کی طرف
حرکت کرتے ہوئے غائب ہو جاتے ہیں جو پہلے ہی سمٹتے سمٹتے ایک نقطہ کی شکل اختیار کر گیا
ہوتا ہے.گو ہم اپنی اصطلاح میں اس کو نقطہ کہتے ہیں.لیکن نہیں جانتے کہ وہ نقطہ ہے بھی کہ
نہیں.کیونکہ اس نقطہ کی کوئی خبر باہر کی دنیا کو معلوم نہیں ہوسکتی.اس کے وجود کا صرف اس
طرح پتہ چلتا ہے کہ ارد گرد بعض دفعہ اتنے بڑے فاصلوں پر سے ستارے ڈول کر اس کی طرف
آجاتے ہیں کہ جن کا فاصلہ شعاع کی رفتار سے ناپا جائے جو تقریباً ایک لاکھ چھیاسی ہزار میل
فی سیکنڈ ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک سال میں ایک شعاع جتنا فاصلہ طے کرتی ہے اس سے
ہزاروں گنا زیادہ فاصلہ کی دوری پر موجو دستارے بھی اس نا قابل فہم نقطہ کی غیر معمولی، بے پناہ
کشش ثقل سے مغلوب ہو کر ڈولنے لگتے ہیں اور اپنے مدار سے ٹوٹ کر قوت کے اس مرکز کی
طرف مائل ہو جاتے ہیں اور بالآخر اس کی طرف سفر کرتے کرتے اس کے اندر ڈوب کر
غائب ہو جاتے ہیں.اور وہ نقطہ پھر بھی ایک نقطہ ہی بنا رہتا ہے جس کے اندر سورج سے
ہزاروں گنا زیادہ مادہ غائب ہونے کے باوجود اس کا کوئی حجم نہیں بڑھتا.اس کو سائنٹفک
اصطلاح میں Event Horizon کہا جاتا ہے اور اس کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ جب دنیا
کے سارے قوانین جن کے تابع تخلیق ایک شکل سے دوسری شکل میں تبدیل ہوتی ہے اور وہ
تمام صفات جو مادہ کی ذاتی صفات ہیں وہ کلیہ اس مادہ سے الگ ہو جائیں اور مادہ ہر قسم کی
ذاتی صفت سے عاری ہو جائے اس کا نام ایوینٹ ہورائزن ہے.یعنی عدم اور وجود کے
درمیان حد فاصل پر ہونے والا واقعہ.اس موقع پر چونکہ مادہ اپنی ہر صفت سے عاری ہو جاتا
ہے اس لئے ہم اس کو عدم کہتے ہیں.مادہ یہاں پہنچ کر کیا شکل اختیار کر جاتا ہے؟ اس کے
148
Page 157
متعلق ہم کچھ نہیں سوچ سکتے کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے کوئی خبر نہیں آتی.یک طرفہ راستہ
ہے اور واپسی کی ایک بھی راہ نہیں ہے.نہ بغیر مرئی ریڈی ایشن کے ذریعہ، نہ ہمیں نظر آنے
والی روشنی کے ذریعہ، نہ کسی اور شکل مثلاً آواز وغیرہ کی شکل میں.کوئی خبر پھر وہاں کی نہیں آتی.مادہ کا ذاتی صفات سے کلیہ مبرا ہونا بالکل وہی چیز ہے جس کو سورۃ فاتحہ نے مَالِكِ يَوْمِ
الدین کے حضور حاضر ہونے کا نام دیا ہے.یعنی ایسی ذات کی طرف لوٹ جانا کہ جب کسی چیز
کی کوئی بھی ذاتی صفت باقی نہیں رہے گی.خدا ہر چیز کا مالک ہوگا اور مخلوق اپنی تمام ذاتی
ملکیتوں اور ذاتی صفات سے عاری ہو جائے گی.گویا اپنے آغا ز کی طرف لوٹ جائے گی اور
اسی کا نام عدم ہے.بغیر صفت کے کسی کے وجود کا تصور ہی نہیں ہوسکتا.اسی لئے سائنسدان
کہتے ہیں کہ عدم کی تعریف ہی یہ ہے کہ کوئی چیز صفات سے کلیۂ عاری ہو جائے.وہ کہاں
کوٹتی ہے؟ اس کے متعلق
وہ کچھ نہیں جان سکتے.وہ شکست کو تسلیم کرتے ہیں اور خواہ انسان اپنی
تحقیقات میں کتنی بھی مزید ترقی کرے وہ تصور کر ہی نہیں سکتا کیونکہ حقیقت میں یہ سب چیزیں
اپنے رب کی طرف کوٹتی ہیں.اسی طرح جاندار اپنے رب کی طرف کو ٹتے ہیں.اسی طرح انسان اپنے رب کی طرف کو ٹتا
ہے.اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کا جو نقشہ کھینچا ہے وہ یہی ہے کہ ہر چیز نے بالآخر ، جب بھی وہ
تخلیق کا جامہ پہنتی ہے، سفر کرتے ہوئے ایک منزل تک پہنچنا ہے جو اس کے خالق یعنی
مالک یوم الدین کی منزل ہے.گویا دنیا میں جب بھی کوئی چیز پیدا ہوتی ہے وہ معا ایک سفر
شروع کردیتی ہے اور وہ سفر بالآخر خدا کی ذات پر اس طرح منتج ہوتا ہے کہ وہ مالک
یوم الدین ہوتا ہے اور ہر چیز اپنی صفات خلقیت سے
کلی طور پر عاری ہو کر پہنچتی ہے.اس سفر کے دور ستے ہیں.سورۃ فاتحہ کی پہلی تین آیات نے اس سفر کا نقشہ تفصیل سے کھینچا
ہے.گومختصر ہے.لیکن اگر آپ غور کریں تو حیرت انگیز تفصیل ان چند الفاظ میں ملتی ہے.الحمد
لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ.اے بنی نوع انسان تم نے بھی آخر وہیں پہنچنا ہے.اس لئے صراط مستقیم کی
149
Page 158
وہ راہ اختیار کرو جو حد کے دروازہ سے شروع ہوتی ہے.حمد باری تعالیٰ سے تم اس سفر میں داخل ہو
گے تو پہلے تمہیں ربوبیت نظر آئے گی.یعنی ہر ادنی چیز کا اعلیٰ حالت میں تبدیل ہوتے رہنا.اور یہ
حالت کلیہ اللہ تعالیٰ کے قبضہ وقدرت میں ہے.اس کے ہر نظام میں تم ربوبیت کا نظام دیکھو گے.ہر چیز جو پیدا ہوتی ہے معا ایک سفر شروع کر دیتی ہے.کوئی چیز بھی ٹھہراؤ کی حالت میں نہیں
ملتی.اس ربوبیت کی حمد کرتے ہوئے تم یہ معلوم کرو گے کہ اگر چہ آغاز میں بھی رحمانیت اور
رحیمیت کا دور تھا یعنی جس کی طرف بسم اللہ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ.میں اشارہ ہے.(اسکی
تفصیل بیان کرنے کا یہاں وقت نہیں) مگر اس کے بعد پھر ایک رحمانیت اور رحیمیت کا تم دور
دیکھو گے اور مذہبی دنیا کے لحاظ سے خدا تمہیں رحمان بھی نظر آئے گا اور رحیم بھی نظر آئے گا.بن
مانگے تمہیں اس نے قرآن عطا فرما دیا جو اس کی رحمانیت کا مظہر ہے جیسا کہ فرمایا: الرحمن -
عَلَّمَ الْقُرْآنَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ (الرحمن (52)
یعنی تخلیق خواہ روحانی دنیا کی ہو یا مادی دنیا کی ، دونوں رحمان سے
نکلتی ہیں.لیکن رحمانیت کا
یہ جلوہ دکھانے کے بعد رحیمیت کے دور میں داخل کر دیا.یعنی جزا و سزا کے دور میں تم اپنے
اعمال کے ذریعہ مزید اچھے بھی بن سکتے ہو، برے بھی بن سکتے ہو.اچھے اعمال کے نتیجہ میں اچھا
نتیجہ پاؤ گے اور برے اعمال کے نتیجہ میں برا نتیجہ دیکھو گے.یہ سب سفر طے کرنے کے بعد تم
اپنے رب کے حضور حاضر ہو جاؤ گے اور تمہارا کچھ بھی نہیں رہے گا.پھر سب کچھ اللہ کی طرف
واپس لوٹ چکا ہوگا.یہ جوسفر بیان فرمایا اس سفر کے اندر رحمانیت میں سے گزرنا اور پھر رحیمیت میں سے گزرنا
ضروری ہے.یعنی ہر چیز جو خدا تعالیٰ کی ربوبیت کا مظہر بنتی ہے.وہ اگر رحمانیت اور رحیمیت
میں سے ہو کر ملِكِ يَوْمِ الدّین تک پہنچے گی تو یہ وہ صراط مستقیم ہے جو انْعَمْتَ عَلَيْهِمُ کی
راہ ہے.اگر شارٹ سرکٹ کرے گی تو پہنچے گی تو پھر بھی ملِكِ يَوْمِ الدِّينِ کے پاس ہی
لیکن اگر رحمانیت کو نظر انداز کر کے پہنچے گی تو مغضوب بن کر پہنچے گی.اگر رحیمیت کو نظر انداز
150
Page 159
کر کے پہنچے گی تو ضاآئین بن کر پہنچے گی.چنانچہ یہی وجہ ہے کہ رحمانیت سے عاری لوگوں کو
مغضوب کہا گیا یعنی یہود کو.اور رحیمیت کی صفت کا انکار کرنے والوں کو ضالین کہا گیا یعنی
نصاری کو.یہود کے متعلق قرآن کریم فرماتا ہے اُن کے دل پتھر ہو گئے تھے.وہ خدا کی رحمانیت سے
منحرف ہو گئے اور رحمانیت کا کوئی جلوہ انہوں نے اختیار نہیں کیا.کامل طور پر سخت دل ہو
گئے.چنانچہ ان کے متعلق قرآن کریم نے فرمایا غیرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ان لوگوں کا رستہ
نہ ہو جو رحمانیت کو نظر انداز کر کے بالآخر ملِكِ يَوْمِ الدین تک پہنچتے ہیں.کیونکہ وہ مغضوب
ہو جاتے ہیں.اور ان لوگوں کا رستہ بھی نہ ہو جو رحیمیت کو نظر انداز کر کے بالآخر ملك
يَوْمِ الدِّينِ تک پہنچتے ہیں کیونکہ وہ ضالین ہو جاتے ہیں.رحیمیت کیا ہے؟ اعمال کے نظام کا ایک نقشہ ہے.جس میں اللہ کے رحم پر سہارا کرتے
ہوئے انسان جو بھی نیک عمل کرتا ہے اس کی نیک جزا پاتا ہے.عیسائیت کی بنیاد اس بات پر
ہے کہ ایسا کوئی خدا ہمیں نظر نہیں آتا جو نیک اعمال کو قبول فرماتے ہوئے اس میں اپنے رحم کا
حصہ شامل کرتے ہوئے ہمیں جزا دے اور ہمیں ہلاکتوں سے نجات بخشے.بلکہ ایسا ظالم خدا نظر
آتا ہے کہ تمام اعمال جو ہم کرتے ہیں خواہ وہ کیسے ہی اعلیٰ پایہ کے ہوں، کیسی ہی حسین شکلیں
اختیار کر جائیں بالآخر خدا اس رنگ میں ”عدل“ کا سلوک کرے گا کہ ہمیں گناہگار ہی لکھے گا
یعنی یہ عجیب عدل کا تصور ہے.تمام زندگی کے نیک اعمال کے بعد بھی ہم گناہگار کے گناہگار
لکھے جائیں گے.محض اس لیے کہ ہمارے آباؤ اجداد نے گناہ کیا تھا.اس لیے رحیمیت کا
کوئی نظام بھی انسان کو بچا نہیں سکتا.چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا اور اس کو
ہماری خاطر مصلوب کیا.یعنی یہ بھی عدل کا عجیب تصور ہے کہ ایک شخص کو بچانے کے لیے
ایک اور بیچارے معصوم آدمی کو سولی پر لٹکا دیا تا کہ جولوگ رحیمیت سے عاری ہو کر کوئی فیض
نہیں پاسکتے میرا بیٹا اُن کے لیے بلاک ہو جائے اور اس کے نتیجہ میں اُن پر رحم کیا جائے.151
Page 160
پس رحیمیت کے نظام کو تہس نہس کر دینا عیسائیت کا نام ہے.یہ عیسائیت کا خلاصہ ہے.آپ جس پہلو سے بھی عیسائیت کو دیکھیں گے وہ رحیمیت کے منکر نظر آئیں گے اپنے نظریات
میں بھی اور اپنے اعمال کے لحاظ سے بھی.اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ضالین ہیں.مومن
کے لئے صراط مستقیم پر چلنا اسی طرح ہے جس طرح ہر دوسری چیز کے لیے ہے.لیکن مومن کی
صراط مستقیم ربوبیت سے ہوتی ہوئی حمد کے دروازہ سے داخل ہوتی ہے.ربوبیت کا نظارہ کرتی
ہوئی وہ رحمانیت میں داخل ہوتی ہے.رحمانیت سے وہ رحیمیت میں چلی جاتی ہے.رحیمیت
سے پھر وہ اپنے مالک یوم الدین یعنی اپنے رب کے حضور حاضر ہو جاتی ہے.یہ وہ راہ ہے جس
كو القِرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمُ.کہا گیا اور جہاں ربوبیت
نظر انداز ہو یا رحمانیت نظر انداز ہو یارحیمیت نظر انداز ہو وہ ساری ٹیڑھی راہیں ہیں اور اللہ کے
غضب کی راہیں ہیں.لیکن سوال یہ ہے کہ حمد کے راستہ سے ہم کس طرح داخل ہوتے ہیں اور
رحمانیت کی راہ سے خدا تک پہنچنے کا اور رحیمیت کی راہ سے خدا تک پہنچنے کا مطلب کیا ہے؟
اس کے تین پہلو ہیں.اول.نظریاتی لحاظ سے انسان کلیہ یہ تسلیم کرے کہ الحمد للہ ساری حمد خالصہ اللہ تعالیٰ
کے لیے ہے جو اب بھی ہے ، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے اور مالک یوم الدین بھی ہے.پھر
یہ ایک الگ مضمون شروع ہو جاتا ہے اس کو میں فی الحال چھوڑ کر اصل مضمون کی طرف جلد
مائل ہونا چاہتا ہوں.دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ نظریہ دل پر وارد ہو جائے اور دل کے جذبات پر بھی قابض ہو جائے.یعنی انسان حمد صرف زبان سے نظریہ کے طور پر بیان نہ کرے.بلکہ دل اس حمد کو محسوس کرے اور
ایک لذت پائے اور ایک محبت محسوس کرے اور اللہ تعالیٰ کے لیے ایک جوش پائے.یہ حمد کی
دوسری شکل ہے.یعنی ذہن سے دل میں ڈوبتی ہے اور نظریہ ایک محبت کی شکل میں ڈھل جاتا
ہے.جذبات کی شکل میں وہ نظریہ موجزن ہو جاتا ہے اور پھر ربوبیت سے اپنا تعلق جوڑتا ہے.152
Page 161
رحمانیت سے اپنا تعلق جوڑتا ہے جس طرح کتا اپنے مالک کے قدموں میں پیار سے لوٹتا پوٹتا
ہے اس طرح جب حمد کا یہ تصور دل میں آتا ہے تو کروٹیں لینے لگتا ہے.تبدیل ہونے والی یا
لوٹنے پوٹنے والی چیز کو قلب کہتے ہیں.پس حقیقی قلب اس وقت بنتا ہے جب اللہ کے
قدموں میں یہ لوٹتا ہے اس کی حمد کی وجہ سے.اس کی حمد سے غیر معمولی طور پر مغلوب ہو کر یہ خدا
کے قدموں میں کروٹیں بدلتا ہے، پیار کے اظہار کرتا ہے.کبھی اس کی ربوبیت پر
واری جاتا ہے.کبھی اس کی رحمانیت پر اور کبھی اس کی رحیمیت پر.اور اس طرح پھر انسان
آخر ما لک یوم الدین تک پہنچ جاتا ہے.اس کا تیسرا درجہ اعمال کا درجہ ہے.حمد کی یہ دونوں شکلیں تب سچی قرار دی جائیں گی اگران
کا اعمال پر بھی اثر پڑے اور اگر اعمال پر اثر نہیں پڑتا تو محض جذباتی تصویریں ہیں.ان کی کوئی
بھی حقیقت نہیں.پھر اعمال کی وہ راہ ہے جس کے لیے انسان کے سامنے بہت ہی مشکلات
پیش آتی ہیں.وہ کہنے کو تو یہ کہہ دیتا ہے اللہ رب ہے لیکن اس ربوبیت کا مظہر بننے کی راہ میں
جب وقتیں پیش آتی ہیں تو اس وقت سمجھ آتی ہے کہ منہ سے تعریف کرنا اور چیز ہے.دل سے
محسوس کرنا اور چیز ہے.اور اعمال میں جاری کرنا بالکل اور چیز ہے.وہ کہ تو دیتا ہے اللہ
ان ہے مگر خود بندوں کے لیے رحمان بننا ایک بہت بڑا کام ہے.اتنا عظیم الشان کام ہے
کہ قدم قدم پر انسان کے سامنے یہ امتحان آتا ہے اور اس میں فیل ہوتا چلا جاتا ہے.منہ سے
رحمان کی تعریف کرتا ہے، دل سے محسوس کرتا ہے کہ ہاں وہ بہت ہی پیاری چیز ہے مگر جب
ایک رستہ اختیار کرنے کا وقت آتا ہے تو رحمانیت کا رستہ چھوڑ کر غضب کا رستہ اختیار کر لیتا
ہے.ایسے شخص کے متعلق ہم یہ کس طرح توقع کر سکتے ہیں کہ وہ مالک یوم الدین تک
رحمانیت کی راہ سے پہنچے گا.اس نے تو خود اپنی آزمائشوں کے وقت میں رحمانیت کی راہ ترک
کی اور مغضوبیت کی راہ اختیار کرلی.یہی رحیمیت کا حال ہے.رحیمیت کی راہ اختیار کرنے کی بجائے انسان ہمیشہ تو نہیں مگر
153
Page 162
اکثر صورتوں میں ایسی راہ اختیار کرتا ہے کہ بندوں سے ان کے اعمال کے مطابق رحمت کا
سلوک نہیں کرتا.مزدور کی مزدوری مارنے والے لوگ، حق سے کم ادا کرنے والے لوگ
سارے وہ لوگ ہیں جو ضالین کے زمرہ میں شمار ہوتے ہیں.مغربی قوموں نے جو
Exploitation یعنی استحصال سے کام لیا ہے، یہ رحیمیت کا عملی انکار ہے.تمام دنیا
میں Capitalists نے جو Exploitation کی ہے اس کے نتیجہ میں پھر آگے اشتراکیت
نے جنم لیا ہے.یہ وہی ضاآئین کی راہ ہے جو رحیمیت کے انکار کے نتیجہ میں پیدا ہوتی ہے.ادنی قوموں سے محنتیں لیں، کام لیے اور ان کو ان کے بدلے پورے نہیں دیئے اور وہ ان
غریب قوموں کا جو جائز حق کھا گئے یہی استحصال ہے.اسی کے نتیجہ میں پھر دنیا میں بڑی بڑی
تباہیاں آئی ہیں اور آفتیں ٹوٹی ہیں.پس ضالین کی راہ جو عیسائیت نے اختیار کی وہ بھی صرف نظریاتی نہ رہی بلکہ عملی شکل میں
ڈھل گئی.اقتصادی نظام کی شکل میں بھی ڈھل گئی.معاشرہ میں بھی ڈھل گئی.تمدن میں بھی
ڈھل گئی.ملوکیت میں بھی ڈھل گئی.ہر چیز پر اثر انداز ہوگئی.تو یہ جو رحیمیت کی راہ کو چھوڑ کر
خدا تک پہنچیں گے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہی ضالین کہلائیں گے اور ان رستوں کو چھوڑنے
کے نتیجہ میں دنیا اور آخرت میں سخت بد انجام
کو پہنچیں گے.حقیقت یہ ہے کہ اس کی مثال ویسی ہی ہے جیسے بجلی ایک قوت کا نام ہے.اس کے بھی
سفر کے رستے مختلف ہو سکتے ہیں.بلب یا کسی اور برقی آلہ کی راہ سے ہو کر بھی وہ اپنے دوسرے
حصہ تک پہنچ جاتی ہے جو اس کا انجام ہے جہاں جا کر وہ Annihilate ہو جاتی ہے اور
براہِ راست بھی بغیر مقررہ راستے کے وہ دوسرے کنارے تک پہنچ سکتی ہے.لیکن اس دوسری
صورت میں سوائے بھسم کر دینے والی آگ کے اس کے سفر کا ماحصل کچھ بھی نہیں ہوتا.پس
اگر وہ بلب یا مشین یا پنکھے یا ریفریجریٹر کے رستے سے ہونے کی بجائے براہ راست وہاں تک
پہنچتی ہے تو جل کر بھسم ہو جاتی ہے.اس کے سوا اس کا کوئی انجام نہیں ہوتا.154
Page 163
پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نے آنا تو میرے پاس ہے.طَوْعًا یا گرھا تم نے میرے
پاس آہی جانا ہے.تم تخلیق کی جو بھی شکلیں ہو مادہ ہو یا نباتات ہو یا حیوان ہو یا انسان ہو بالآخر تم
نے میرے پاس پہنچنا ہے اور ایسی حالت میں پہنچنا ہے کہ تمہارا اپنا کچھ بھی نہیں رہے گا.اُس
وقت جو کچھ میں تمہیں عطا کروں گا اس کی بنا یہ ہوگی کہ اگر تم رحمانیت کے رستہ سے مجھ تک آؤ
گے اور رحیمیت کے رستہ سے مجھ تک آؤ گے تو مجھے انعام دینے والا پاؤ گے.جو کچھ میں دوں گا
پھر وہ میری طرف سے ہوگا.تمہاری ذاتی مالکیت تو پھر بھی کچھ نہیں ہو گی.لیکن ان رستوں کو
نظر انداز کرو گے تو تمہارا کچھ بھی باقی نہیں رہے گا.میرے حضور حاضر ہونے سے پہلے پہلے
رحمانیت اور رحیمیت کے رستے تمہیں تین طریق پر طے کرنے ہوں گے.نظریاتی لحاظ سے بھی
اختیار کرنے پڑیں گے قلبی لحاظ سے بھی اختیار کرنے پڑیں گے اور عملی لحاظ سے بھی اختیار
کرنے پڑیں گے.پس یہی سچی حمد ہے جس کا نقشہ قرآن کریم نے کھینچا ہے.( خطبه جمعه فرمودہ حضرت خلیفہ امسیح الرابع رحمہ اللہ ، فرمودہ 29 /اکتوبر 1982 ء.خطباتِ طاہر جلد اوّل صفحہ 231 تا240)
155
Page 165
سورة البقرة - آيات 1 تا 17
XXXXXXXXXXXXXX
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
1 - (میں) اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا
( اور ) بار بار رحم کرنے والا ہے (پڑھتا ہوں.)
المة
2 میں اللہ سب سے زیادہ جاننے والا ہوں.ذلِكَ الْكِتُبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى 3.یہی کامل کتاب ہے.اس (امر) میں کوئی
لِلْمُتَّقِينَ
شک نہیں.متقیوں کو ہدایت دینے والی ہے.الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ 4.جو غیب پر ایمان لاتے اور نماز کو قائم
رکھتے ہیں اور جو ( کچھ ) ہم نے انہیں دیا ہے
الصَّلوةَ وَ مِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنْفِقُونَ
اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں.وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ 5.اور جو مجھ پر نازل کیا گیا ہے یا جو مجھ سے پہلے نازل
وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ کیا گیا تھا اس پر ایمان لاتے ہیں اور آئندہ ہونے
والی ( موعود باتوں ) پر ( بھی ) یقین رکھتے ہیں.هُمْ يُوقِنُونَ )
أوليكَ عَلَى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ ۚ وَ أُولَبِكَ 6.یہ لوگ (یقیناً) اس ہدایت پر ( قائم ) ہیں جو اُن
کے رب کی طرف سے (آئی) ہے اور یہی لوگ
هُمُ الْمُفْلِحُونَ )
کامیاب ہونے والے ہیں.اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ 7.ایسے لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے (اور ) تیرا
اُن کو ڈرانا یا نہ ڈرانا ان کے لئے یکساں (اثر پیدا
انْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ )
کرتا) ہے ( جب تک وہ اس حالت کو نہ بدلیں )
خَتَمَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى
ایمان نہیں لائیں گے.8.اللہ نے اُن کے دلوں پر اور اُن کے کانوں پر مہر کر
157
Page 166
وَ عَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ (پڑا ہوا) ہے اور
عَذَابٌ عَظِيمُن
اُن کے لئے ایک بڑا عذاب ( مقدر) ہے.وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ 9.اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم
الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ
ج
اللہ پر اور آنے والے دن پر ایمان رکھتے ہیں
حالانکہ وہ ہر گز ایمان نہیں رکھتے.يُخْدِعُونَ اللهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا 10.وہ اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں
وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ دھوکا دینا چاہتے ہیں مگر ( واقعہ میں ) وہ اپنے سوا کسی
کو دھو کہ نہیں دیتے.اور وہ سمجھتے نہیں.وَمَا يَشْعُرُونَ
فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللهُ 11.ان کے دلوں میں ایک بیماری تھی.پھر اللہ نے ان کی
مَرَضًا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوْا بیماری کو (اور بھی) بڑھا دیا.اور انہیں ایک دردناک
يَكْذِبُونَ
عذاب پہنچ رہا ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے.وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ 12.اور جب اُن سے کہا جائے (کہ) زمین میں
فساد نہ کرو.تو کہتے ہیں ہم تو صرف اصلاح کرنے
قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ
والے ہیں.أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ 13 - ( کان کھول کر) سنو! یہی لوگ بلاشبہ فساد
کرنے والے ہیں مگر وہ (اس حقیقت کو ) سمجھتے نہیں.لا يَشْعُرُونَ
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مِنُوْا كَمَا أَمَنَ النَّاسُ قَالُوا 14.اور جب انہیں کہا جائے کہ (اسی طرح)
آنُؤْمِنُ كَمَا أَمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ ایمان لاؤ جس طرح (دوسرے) لوگ ایمان
هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَّا يَعْلَمُوْنَ )
لائے ہیں تو کہتے ہیں کہ کیا ہم (اس طرح) ایمان
لائیں جس طرح بیوقوف (لوگ) ایمان لائے
ہیں.یا درکھو! ( یہ جھوٹ بول رہے ہیں ) وہ خود ہی
بیوقوف ہیں مگر ( اس بات کو ) جانتے نہیں.158
Page 167
لا
وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوْا قَالُوا أَمَنَّا وَإِذَا 15.اور جب وہ ان لوگوں سے ملیں جو ایمان لائے
ہیں تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو (اس رسول کو ) مانتے
خَلَوْا إِلى شَيْطِيْنِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ
ہیں.اور جب وہ اپنے سرغنوں سے علیحدگی میں ملیں تو
کہہ دیتے ہیں کہ ہم یقیناً تمہارے ساتھ ہیں.ہم تو
صرف ان مومنوں سے ) ہنسی کر رہے تھے.إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ
اللهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي 16.اللہ انہیں ( اُن کی ) ہنسی کی سزا دے گا اور
انہیں اپنی سرکشیوں میں بہکتے ہوئے چھوڑ دے گا.طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ )
أُولَبِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَةَ بِالْهُدَى 17.یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کو چھوڑ کر
فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا گمراہی کو اختیار کر لیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ نہ تو انہیں
دنیوی فائدہ پہنچا اور نہ انہوں نے ہدایت پائی.مُهْتَدِينَ
159
Page 168
سورۃ البقرہ کی ابتدائی سترہ آیات کے حوالہ سے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام
کے بعض ارشادات درج ذیل ہیں.اس سورۃ ( البقرہ : ناقل ) میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کی بہت تفصیل ہے اور امر
اور نہی کھول کر بیان کیا گیا ہے اور صبر اور ایثار کی بہت تاکید ہے.( مکتوبات جلد پنجم نمبر پنجم صفحہ 150 )
سورۃ البقرہ کی آیت دو اور تین کے تحت آپ نے فرمایا:
جب تک کسی کتاب کے عِلل اربعہ کامل نہ ہوں وہ کتاب کامل نہیں کہلا سکتی اس
لئے خدا تعالیٰ نے ان آیات میں قرآن شریف کے علل اربعہ کا ذکر فرما دیا ہے.اور وہ
چار ہیں.( 1 ) علت فاعلی (2) علت مادی (3) علت صوری (4) علتِ غائی.اور ہر چہار
کامل درجہ پر ہیں.پس اللہ علت فاعلی کے کمال کی طرف اشارہ کرتا ہے جس کے معنی ہیں: انا اللہ اعلم یعنی کہ میں
جو خدائے عالم الغیب ہوں میں نے اس کتاب کو اُتارا ہے پس چونکہ خدا اس کتاب کی علت فاعلی
ہے اس لئے اس کتاب کا فاعل ہر ایک فاعل سے زبر دست اور کامل ہے.اور علت مادی کے کمال کی طرف اشارہ کرتا ہے یہ فقره که ذلك الكتب یعنی یہ وہ کتاب
ہے جس نے خدا کے علم سے خلعت وجود پہنا ہے اور اس میں کچھ شک نہیں کہ خدا تعالیٰ کا علم
تمام علوم سے کامل تر ہے اور علتِ صوری کے کمال کی طرف اشارہ کرتا ہے یہ فقرہ لا ريب
فيه - یعنی یہ کتاب ہر ایک غلطی اور شک و شبہ سے پاک ہے اور اس میں کیا شک ہے کہ جو
کتاب خدا تعالیٰ کے علم سے نکلی ہے وہ اپنی صحت اور ہر ایک عیب سے مبرا ہونے میں
بے مثل و بے مانند ہے اور لاریب ہونے میں اکمل اور اتم ہے
160
Page 169
اور علت غائی کے کمال کی طرف اشارہ کرتا ہے یہ فقرہ کہ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ یعنی یہ کتاب
ہدایت کامل متقین کے لئے ہے اور جہاں تک انسانی سرشت کے لئے زیادہ سے زیادہ ہدایت
ہو سکے وہ اس کتاب کے ذریعہ سے ہوتی ہے.(حقیقۃ الوحی، روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 136 ، 137 حاشیہ)
اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کی عِلتِ غائی بیان کرنے میں فرمایا ہے ھدی
للْمُتَّقِينَ.یہ نہیں فرمایا که هُدًى تِلْفَاسِقِينَ یا هُدًى لِّلْكَافِرِينَ ابتدائی تقویٰ جس کے
حصول سے مشتقی کا لفظ انسان پر صادق آ سکتا ہے وہ ایک فطرتی حصہ ہے کہ جو سعیدوں کی
خلقت میں رکھا گیا ہے اور ربوبیت اولیٰ اس کی مربی اور وجود بخش ہے جس سے متقی کا پہلا
تولد ہے مگر وہ اندرونی نور جو روح القدس سے تعبیر کیا گیا ہے وہ عبودیت خالصہ تامہ اور
ربوبیت کامله مستجمعہ کے پورے جوڑ واتصال سے بطرز ثُمَّ انْشَأْنَهُ خَلْقًا أَخَرَ
(المؤمنون 15) کے پیدا ہوتا ہے اور یہ ربوبیتِ ثانیہ ہے جس سے مشتقی تولد ثانی پاتا ہے اور
ملکوتی مقام پر پہنچتا ہے اور اس کے بعد ربوبیت ثالثہ کا درجہ ہے جو خلق جدید سے موسوم ہے
جس سے متقی لاہوتی مقام پر پہنچتا ہے اور تولد ثالث پاتا ہے.(ازالہ اوہام، روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 558 تا560 حاشیہ)
اور ان آیات میں جو معرفت کا نکتہ خفی ہے وہ یہ ہے کہ آیات ممدوحہ بالا میں خدا تعالیٰ
نے یہ فرمایا ہے کہ الم ذَلِكَ الْكِتَبُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ یعنی یہ وہ کتاب ہے جو
خدا تعالیٰ کے علم سے ظہور پذیر ہوتی ہے اور چونکہ اس کا علم جہل اور نسیان سے پاک ہے اس
لئے یہ کتاب ہر ایک شک وشبہ سے خالی ہے اور چونکہ خدا تعالیٰ کا علم انسانوں کی تکمیل کے لئے
اپنے اندر ایک کامل طاقت رکھتا ہے اس لئے یہ کتاب متقین کے لئے ایک کامل ہدایت ہے
اور اُن کو اس مقام تک پہنچاتی ہے جو انسانی فطرت کی ترقیات کے لئے آخری مقام ہے اور
خدا ان آیات میں فرماتا ہے کہ متقی وہ ہیں کہ جو پوشیدہ خدا پر ایمان لاتے ہیں اور نماز کو قائم
کرتے ہیں اور اپنے مالوں میں سے کچھ خدا کی راہ میں دیتے ہیں اور قرآن شریف اور پہلی
161
Page 170
کتابوں پر ایمان لاتے ہیں وہی ہدایت کے سر پر ہیں اور وہی نجات پائیں گے.ان آیات سے یہ تو معلوم ہوا کہ نجات بغیر نبی کریم پر ایمان لانے اور اس کی ہدایات
نماز وغیرہ کے بجالانے کے نہیں مل سکتی.اور جھوٹے ہیں وہ لوگ جو نبی کریم کا دامن چھوڑ کر
محض خشک توحید سے نجات ڈھونڈھتے ہیں مگر یہ عقدہ قابل حل رہا کہ جبکہ وہ لوگ ایسے راستباز
ہیں کہ پوشیدہ خدا پر ایمان لاتے اور نماز بھی ادا کرتے اور روزہ بھی رکھتے ہیں اور اپنے مالوں
میں سے خدا کی راہ میں کچھ دیتے ہیں اور قرآن شریف اور پہلی کتابوں پر ایمان بھی رکھتے ہیں تو
پھر یہ فرمانا کہ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ یعنی اُن کو یہ کتاب ہدایت دے گی اِس کے کیا معنی ہیں؟ وہ تو
ان سب باتوں کو بجالا کر پہلے ہی سے ہدایت یافتہ ہیں اور حاصل شدہ کو حاصل کرانا یہ تو ایک
امر عبث معلوم ہوتا ہے.اس کا جواب یہ ہے کہ وہ لوگ باوجود ایمان اور عمل صالح کے کامل استقامت اور کامل ترقی
کے محتاج ہیں جس کی رہنمائی صرف خدا ہی کرتا ہے انسانی کوشش کا اس میں دخل نہیں.استقامت سے مُراد یہ ہے کہ ایسا ایمان دل میں رچ جائے کہ کسی ابتلاء کے وقت ٹھوکر نہ
مشقت
کھاویں اور ایسے طرز اور ایسے طور پر اعمال صالحہ صادر ہوں کہ اُن میں لذت پیدا ہو اور مشہ
اور تلخی محسوس نہ ہو اور اُن کے بغیر جی ہی نہ سکیں گویا وہ اعمال رُوح کی غذا ہو جائیں اور اُس کی
روٹی بن جائیں اور اس کا آب شیریں بن جائیں کہ بغیر اس کے زندہ نہ رہ سکیں.غرض
استقامت کے بارے میں ایسے حالات پیدا ہو جائیں جن کو انسان محض اپنی سعی سے پیدا نہیں کر
سکتا بلکہ جیسا کہ روح کا خدا کی طرف سے فیضان ہوتا ہے وہ فوق العادت استقامت بھی خدا کی
طرف سے پیدا ہو جائے.اور ترقی سے مُراد یہ ہے کہ وہ عبادت اور ایمان جو انسانی کوششوں کی انتہا ہے اس کے
علاوہ وہ حالات پیدا ہو جائیں جو محض خدا تعالیٰ کے ہاتھ سے پیدا ہو سکتے ہیں.یہ بات ظاہر ہے
کہ خدا تعالیٰ پر ایمان لانے کے بارے میں انسانی سعی اور عقل صرف اس حد تک رہبری کرتی
162
Page 171
ہے کہ اس پوشیدہ خدا پر جس کا چہرہ نہیں دیکھا گیا ایمان لایا جائے اسی وجہ سے شریعت جو
انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف دینا نہیں چاہتی اس بات کے لئے مجبور نہیں کرتی کہ
انسان اپنی طاقت سے ایمان بالغیب سے بڑھ کر ایمان حاصل کرے.ہاں ! راستبازوں کو اسی
آیت هُدًى لِلْمُتَّقین میں وعدہ دیا گیا ہے کہ جب وہ ایمان بالغیب پر ثابت قدم ہو جائیں اور
جو کچھ وہ اپنی سعی سے کر سکتے ہیں کر لیں تب خدا ایمان کی حالت سے عرفان کی حالت تک ان کو
پہنچا دے گا اور اُن کے ایمان میں ایک اور رنگ پیدا کر دے گا.قرآن شریف کی سچائی کی یہ ایک نشانی ہے کہ وہ جو اس کی طرف آتے ہیں اُن کو اُس
مرتبہ ایمان اور عمل پر رکھنا نہیں چاہتا کہ جو وہ اپنی کوشش سے اختیار کرتے ہیں کیونکہ اگر
ایسا ہوتو کیونکر معلوم ہو کہ خدا موجود ہے بلکہ وہ انسانی کوششوں پر اپنی طرف سے ایک شمرہ
مرتب کرتا ہے جس میں خدائی چمک اور خدائی تصرف ہوتا ہے مثلاً جیسا کہ میں نے بیان کیا
انسان خدا پر ایمان لانے کے بارہ میں اس سے زیادہ کیا کر سکتا ہے کہ وہ اس پوشیدہ خدا پر
ایمان لاوے جس کے وجود پر ذرہ ذرہ اس عالم کا گواہ ہے مگر انسان کی یہ تو طاقت ہی نہیں
ہے کہ محض اپنے ہی قدموں اور اپنی ہی کوشش اور اپنے ہی زور بازو سے خدا کے انوارِ
اُلوہیت پر اطلاع پاوے اور ایمانی حالت سے عرفانی حالت تک پہنچ جاوے اور مشاہدہ اور
ریت کی کیفیت اپنے اندر پیدا کر لے.اسی طرح انسانی سعی اور کوشش نماز کے ادا کرنے میں اس سے زیادہ کیا کر سکتی ہے کہ
جہاں تک ہو سکے پاک اور صاف ہو کر اور نفی خطرات کر کے نماز ادا کریں اور کوشش کریں
کہ نماز ایک گری ہوئی حالت میں نہ رہے اور اس کے جس قدر ارکان حمد وثنا حضرت عزت اور
توبہ واستغفار اور دعا اور درود ہیں وہ دلی جوش سے صادر ہوں لیکن یہ تو انسان کے اختیار میں نہیں
ہے کہ ایک فوق العادت محبت ذاتی اور خشوع ذاتی اور محویت سے بھرا ہوا ذوق وشوق اور ہر
ایک کدورت سے خالی حضور اُس کی نماز میں پیدا ہو جائے گویا وہ خدا کو دیکھ لے اور ظاہر ہے
163
Page 172
کہ جب تک نماز میں یہ کیفیت پیدا نہ ہو وہ نقصان سے خالی نہیں.اسی وجہ سے خدا تعالیٰ نے
فرمایا کہ متقی وہ ہیں جو نماز کو کھڑی کرتے ہیں اور کھڑی وہی چیز کی جاتی ہے جو گرنے کے
لئے مستعد ہے.آیت يُقِيمُونَ الصَّلوة کے یہ معنی ہیں کہ جہاں تک اُن سے ہو سکتا ہے نماز کو قائم
کرنے کے لئے کوشش کرتے ہیں اور تکلف اور مجاہدات سے کام لیتے ہیں مگر انسانی
کوششیں بغیر خدا تعالیٰ کے فضل کے بیکار ہیں.اس لئے اس کریم و رحیم نے فرمایا: ھدی
للْمُتَّقِین یعنی جہاں تک ممکن ہو وہ تقویٰ کی راہ سے نماز کی اقامت میں کوشش کریں.پھر اگر
وہ میرے کلام پر ایمان لاتے ہیں تو میں ان کو فقط انہی کی کوشش اور سعی پر نہیں چھوڑوں گا بلکہ
میں آپ ان کی دستگیری کروں گا.تب اُن کی نماز ایک اور رنگ پکڑ جائے گی اور ایک اور
کیفیت اُن میں پیدا ہو جائے گی جو اُن کے خیال و گمان میں بھی نہیں تھی.یہ فضل محض اس لئے
ہوگا کہ وہ خدا تعالیٰ کے کلام قرآن شریف پر ایمان لائے اور جہاں تک اُن سے ہو سکا اُس
کے احکام کے مطابق عمل میں مشغول رہے.غرض نماز کے متعلق جس زائد ہدایت کا وعدہ ہے
وہ یہی ہے کہ اس قدر طبعی جوش اور ذاتی محبت اور خشوع اور کامل حضور میسر آ جائے کہ انسان کی
آنکھ اپنے محبوب حقیقی کے دیکھنے کے لئے کھل جائے اور ایک خارق عادت کیفیت مشاہدہ
جمال باری کی میسر آ جائے جو لذاتِ روحانیہ سے سراسر معمور ہو اور دنیوی رذایل اور انواع و
اقسام کے معاصی قولی اور فعلی اور بصری اور سماعی سے دل کو متنفر کر دے.جیسا کہ اللہ تعالیٰ
فرماتا ہے : اِنَّ الْحَسَنتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاتِ (هود 115)
ایسا ہی مالی عبادت جس قدر انسان اپنی کوشش سے کرسکتا ہے وہ صرف اس قدر ہے کہ
اپنے اموال مرغوبہ میں سے کچھ خدا کے لئے دیوے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی سورت میں فرمایا
ہے : وَمَا رَزَقُهُم يُنفِقُونَ اور جیسا کہ ایک دوسری جگہ فرمایا ہے لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى
تُنْفِقُوا (ال عمران 93 لیکن ظاہر ہے کہ اگر مالی عبادت میں انسان صرف اسی قدر بجا
164
Page 173
لاوے کہ اپنے اموال محبوبہ مرغوبہ میں سے کچھ خدا تعالیٰ کی راہ میں دیوے تو یہ کچھ کمال نہیں ہے
کمال تو یہ ہے کہ ماسویٰ سے بکلی دست بردار ہو جائے اور جو کچھ اُس کا ہے وہ اُس کا نہیں
بلکہ خدا کا ہو جائے یہاں تک کہ جان بھی خدا تعالیٰ کی راہ میں فدا کرنے کے لئے طیار ہو کیونکہ وہ بھی
مما رزقتهُمْ میں داخل ہے.خدا تعالیٰ کا منشاء اُس کے قول مما رزقنا سے صرف درہم و دینار نہیں
ہے بلکہ یہ بڑا وسیع لفظ ہے جس میں ہر ایک وہ نعمت داخل ہے جو انسان کو دی گئی ہے.غرض اس جگہ بھی هُدًى لِلْمُتَّقِينَ فرمانے سے خدا تعالیٰ کا یہ منشاء ہے کہ جو کچھ انسان کو
ہر ایک قسم کی نعمت مثلاً اُس کی جان اور صحت اور علم اور طاقت اور مال وغیرہ میں سے دیا گیا
ہے اس کی نسبت انسان اپنی کوشش سے صرف مِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنْفِقُونَ تک اپنا اخلاص
ظاہر کر سکتا ہے اور اس سے بڑھ کر بشری قوتیں طاقت نہیں رکھتیں لیکن خدا تعالیٰ کا قرآن
شریف پر ایمان لانے والے کے لئے اگر وہ مما رَزَقُنُهُمْ يُنْفِقُونَ کی حد تک اپنا صدق
ظاہر کرے گا بموجب آیت هُدًى لِلْمُتّقین کے یہ وعدہ ہے کہ خدا تعالیٰ اس قسم کی عبادات
میں بھی کمال تک اُس کو پہنچا دے گا اور کمال یہ ہے کہ اُس کو یہ قوت ایثار بخشی جائے گی کہ وہ
شرح صدر سے یہ سمجھ لے گا کہ جو کچھ اس کا ہے خدا کا ہے اور کبھی کسی کو محسوس نہیں کرائے گا
کہ یہ چیزیں اس کی تھیں جس کے ذریعہ سے اس نے نوع انسان کی خدمت کی.مثلاً احسان
کے ذریعہ سے کبھی انسان کسی کو محسوس کراتا ہے کہ اُس نے اپنا مال دوسرے کو دیا مگر یہ ناقص
حالت ہے کیونکہ وہ تبھی محسوس کرے گا کہ جب اس چیز کو اپنی چیز سمجھے گا.پس جب بموجب
آیت هُدًى لِلْمُتَّقین کے خدا تعالیٰ قرآن شریف پر ایمان لانے والے کو اس مقام سے
ترقی بخشے گا تو وہ یہاں تک اپنی تمام چیزوں کو خدا کی چیزیں سمجھ لے گا کہ محسوس کرانے کی مرض
بھی اُس کے دل میں سے جاتی رہے گی اور نوع انسان کے لئے ایک مادری ہمدردی اُس کے
دل میں پیدا ہو جائے گی بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اور کوئی چیز اس کی اپنی نہیں رہے گی بلکہ سب
خدا کی ہو جائے گی اور یہ تب ہوگا کہ جب وہ سچے دل سے قرآن شریف اور نبی کریم پر ایمان
165
Page 174
لائے گا بغیر اس کے نہیں.پس کس قدر گمراہ وہ لوگ ہیں جو بغیر متابعت قرآن شریف اور
رسول کریم کے صرف خشک تو حید کو موجب نجات ٹھہراتے ہیں بلکہ مشاہدہ ثابت کر رہا ہے کہ
ایسے لوگ نہ خدا پر سچا ایمان رکھتے ہیں نہ دنیا کے لالچوں اور خواہشوں سے پاک ہو سکتے ہیں
چہ جائیکہ وہ کسی کمال تک ترقی کریں اور یہ بات بھی بالکل غلط اور کورانہ خیال ہے کہ انسان خود
بخود نعمت توحید حاصل کر سکتا ہے بلکہ تو حید خدا کی کلام کے ذریعہ سے ملتی ہے اور اپنی طرف سے
جو کچھ سمجھتا ہے وہ شرک سے خالی نہیں.اسی طرح خدا تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانے کے
بارے میں انسانی کوشش صرف اس حد تک ہے کہ انسان تقویٰ اختیار کر کے اس کی کتاب پر
ایمان لاوے اور صبر سے اُس کی پیروی کرے اس سے زیادہ انسان میں طاقت نہیں لیکن خدا
تعالی نے آیت هُدًى لِلْمُتَّقین میں یہ وعدہ فرمایا ہے کہ اگر اس کی کتاب اور رسول پر کوئی
ایمان لائے گا تو وہ مزید ہدایت کا مستحق ہوگا اور خدا اس کی آنکھ کھولے گا اور اپنے مکالمات و
مخاطبات سے مشرف کرے گا اور بڑے بڑے نشان اُس کو دکھائے گا.یہاں تک کہ وہ اسی
دنیا میں اُس کو دیکھ لے گا کہ اس کا خدا موجود ہے اور پوری تسلی پائے گا.خدا کا کلام کہتا ہے
کہ اگر تو میرے پر کامل ایمان لاوے تو میں تیرے پر بھی نازل ہوں گا.اسی بنا پر حضرت
امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اِس اخلاص اور محبت اور شوق سے خدا کے
کلام کو پڑھا کہ وہ الہامی رنگ میں میری زبان پر بھی جاری ہو گیا.(حقیقۃ الوحی، روحانی خزائن جلد 22 صفحه 135 تا 141)
ہر شے کی چار علتیں ہوتی ہیں یہاں بھی ان علل اربعہ کو بیان کیا ہے اور وہ علیل اربعہ
یہ ہوتی ہیں علت فاعلی.عِلتِ صوری.عِلتِ مادی.عِلتِ غائی.اس مقام پر قرآن شریف
کی چار علتوں کا ذکر کیا.علت فاعلی تو اس کتاب کی اللہ ہے اور الٹر کے معنے میرے نزدیک انا الله اعلم یعنی
میں اللہ وہ ہوں جو سب سے زیادہ علم رکھتا ہوں.اور علت مادى ذلك الكتب ہے یعنی یہ
166
Page 175
کتاب اس خدا کی طرف سے آئی ہے جو سب سے زیادہ علم رکھتا ہے.اور علتِ صوری
لا رَيْبَ فِیهِ ہے یعنی اس کتاب کی خوبی اور کمال یہ ہے کہ اس میں کسی قسم کا شک و شبہ ہی نہیں
جو بات ہے مستحکم اور جو دعویٰ ہے وہ مدلل اور روشن اور علتِ غائی اس کتاب کی ھدی
للْمُتَّقِينَ ہے یعنی اس کتاب کے نزول کی غرض و غایت یہ ہے کہ متقیوں کو ہدایت کرتی ہے.یہ چاروں علتیں بیان کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے متقیوں کے عام صفات بتائے ہیں کہ وہ
مشقی کون ہوتے ہیں جو ہدایت پاتے ہیں الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلوةَ وَهِمَا
رَزَقُتُهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ
يُوقِنُونَ یعنی وہ متقی ہوتے ہیں جو خدا پر جو ہنوز پردہ غیب میں ہوتا ہے ایمان لاتے ہیں اور
نماز کو کھڑا کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں اور وہ
ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر جو تجھ پر نازل کی ہے اور جو کچھ تجھ سے پہلے نازل ہوا
اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں.یہ صفات متقی کے بیان فرمائے.اب یہاں بالطبع ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کتاب کی غرض و غایت تو یہ بتائی
هدًى لِّلْمُتَّقِينَ اور پھر متقیوں کے صفات بھی وہ بیان کئے جوسب کے سب ایک باخدا انسان
میں ہوتے ہیں یعنی خدا پر ایمان لاتا ہو، نماز پڑھتا ہو، صدقہ دیتا ہو، کتاب اللہ کو مانتا ہو،
قیامت پر یقین رکھتا ہو پھر جو شخص پہلے ہی سے ان صفات سے متصف ( ہے ) اور وہ متقی
کہلاتا ہے اور ان امور کا پابند ہے تو پھر وہ ہدایت کیا ہوئی ؟ جو اس کتاب کے ذریعہ اُس نے
حاصل کی اس میں وہ امر زائد کیا ہے جس کے لئے یہ کتاب نازل ہوئی ہے؟ اس سے صاف
معلوم ہوتا ہے کہ وہ کوئی اور امر ہے جو اس ہدایت میں رکھا گیا ہے کیونکہ یہ امور جو بطور صفات
متقین بیان فرمائے ہیں یہ تو اس ہدایت کے لئے جو اس کتاب کا اصل مقصد اور غرض ہے بطور
شرائط ہیں ورنہ وہ ہدایت اور چیز ہے اور وہ ایک اعلیٰ امر ہے جو خدا تعالیٰ نے مجھ پر ظاہر کیا
ہے اور جس کو میں بیان کرتا ہوں.پس یاد رکھو کہ متقی کی صفات میں سے پہلی صفت یہ بیان کی يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ یعنی غیب پر
167
Page 176
ایمان لاتے ہیں.یہ مومن کی ایک ابتدائی حالت کا اظہار ہے کہ جن چیزوں کو اس نے نہیں
دیکھا ان کو مان لیا ہے.غیب اللہ تعالیٰ کا نام ہے اور اس غیب میں بہشت، دوزخ ، حشر اجساد
اور وہ تمام امور جو ابھی تک پردہ غیب میں میں شامل ہیں.اب ابتدائی حالت میں تو مومن ان پر
ایمان لاتا ہے.لیکن ہدایت یہ ہے کہ اس حالت پر اسے ایک انعام عطا ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ
اس کا علم غیب سے انتقال کر کے شہود کی طرف آ جاتا ہے اور اس پر پھر ایسا زمانہ آ جاتا ہے کہ
جن باتوں پر وہ پہلے غائب کے طور پر ایمان لاتا تھا وہ ان کا عارف ہو جاتا ہے اور وہ امور جوا بھی
تک مخفی تھے اس کے سامنے آ جاتے ہیں اور حالتِ شہود میں انہیں دیکھتا ہے.پھر وہ خدا کو
غیب نہیں مانتا بلکہ اسے دیکھتا ہے اور اس کی تجلی سامنے رہتی ہے.غرض اس غیب کے بعد
شہود کا درجہ اسے عطا کیا جاتا ہے جیسے ایمان کے بعد عرفان کا مرتبہ ملتا ہے.وہ خدا تعالیٰ کو اسی
عالم میں دیکھ لیتا ہے اور اگر اس کو یہ مرتبہ عطا نہ ہوتا تو پھر يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ کے مصداق کو کوئی
ہدایت اور انعام عطا نہ ہوتا.اس کے لئے قرآن شریف گویا موجب ہدایت نہ ہوتا.مگر ایسا نہیں
ہوتا اور اس کے لئے ہدایت یہی ہے کہ اس کے ایمان کو حالتِ غیب سے منتقل کر کے حالتِ
شہود میں لے آتا ہے اور اس پر دلیل یہ ہے مَن كَانَ في هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمى (بني
اسرائیل:73) یعنی جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ دوسرے عالم میں بھی اندھا اُٹھایا جاوے گا.اس
نابینائی سے یہی مراد ہے کہ انسان خدا تعالیٰ کی تجلی اور ان امور کو جو حالت غیب میں ہیں اسی عالم
میں مشاہدہ نہ کرے اور یہ نابینائی کا کچھ حصہ غیب والے میں پایا جاتا ہے لیکن هُدًى لِلْمُتَّقِينَ
کے موافق جو شخص ہدایت پالیتا ہے اس کی وہ نابینائی دور ہوجاتی ہے اور وہ اس حالت سے ترقی کر
جاتا ہے اور وہ ترقی اس کلام کے ذریعہ سے یہ ہے کہ ایمان بالغیب کے درجہ سے شہود کے درجہ
پر پہنچ جاوے گا اور اس کے لئے یہی ہدایت ہے.متقی کی دوسری صفت یہ ہے يُقِيمُونَ الصَّلوۃ یعنی وہ نماز کو کھڑی کرتے ہیں.متقی
سے جیسے ہو سکتا ہے نماز کھڑی کرتا ہے.یعنی کبھی اس کی نماز گر پڑتی ہے پھر اسے کھڑا کرتا
168
Page 177
ہے.یعنی متقی خدا سے ڈرا کرتا ہے اور وہ نماز کو قائم کرتا ہے اس حالت میں مختلف قسم کے
وساوس اور خطرات بھی ہوتے ہیں جو پیدا ہو کر اس کے حضور میں بارج ہوتے ہیں اور نماز کو گرا
دیتے ہیں لیکن یہ نفس کی اس کشاکش میں بھی نماز کو کھڑا کرتا ہے.کبھی نماز گرتی ہے مگر یہ پھر
اسے کھڑا کرتا ہے اور یہی حالت اس کی رہتی ہے کہ وہ تکلف اور کوشش سے بار بار اپنی نماز کو
کھڑا کرتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس کلام کے ذریعہ ہدایت عطا کرتا ہے.الحکم نمبر 2 جلد 10 مؤرخہ 17 جنوری 1906 ، صفحہ 5)
اس وقت بجائے يُقِيمُونَ الصَّلوة کے ان کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ وہ اس کشمکش
اور وساوس کی زندگی سے نکل جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعہ انہیں وہ مقام عطا
کرتا ہے جس کی نسبت فرمایا ہے کہ بعض آدمی ایسے کامل ہو جاتے ہیں کہ نماز ان کے لئے
بمنزلہ غذا ہو جاتی ہے اور نماز میں ان کو وہ لذت اور ذوق عطا کیا جاتا ہے جیسے سخت پیاس کے
وقت ٹھنڈا پانی پینے سے حاصل ہوتی ہے کیونکہ وہ نہایت رغبت سے اسے پیتا ہے اور خوب سیر
ہو کر حظ حاصل کرتا ہے یا سخت بھوک کی حالت ہو اور اسے نہایت ہی اعلیٰ درجہ کا خوش ذائقہ
کھانا مل جاوے جس کو کھا کر وہ بہت ہی خوش ہوتا ہے، یہی حالت پھر نماز میں ہو جاتی
ہے.وہ نماز اس کے لئے ایک قسم کا نشہ ہوجاتی ہے جس کے بغیر وہ سخت کرب
و اضطراب محسوس کرتا ہے لیکن نماز کے ادا کرنے سے اس کے دل میں ایک خاص سرور اور
ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے جس کو ہر شخص نہیں پاسکتا اور نہ الفاظ میں یہ لذت بیان ہوسکتی ہے اور
انسان ترقی کر کے ایسی حالت میں پہنچ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اسے ذاتی محبت ہو جاتی ہے
اور اس کو نماز کے کھڑے کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی اس لئے کہ وہ نماز اس کی کھڑی
ہی ہوتی ہے اور ہر وقت کھڑی ہی رہتی ہے اس میں ایک طبعی حالت پیدا ہو جاتی ہے اور ایسے
انسان کی مرضی خدا تعالیٰ کی مرضی کے موافق ہوتی ہے.انسان پر ایسی حالت آتی ہے کہ اس کی
محبت اللہ تعالیٰ سے محبت ذاتی کا رنگ رکھتی ہے اس میں کوئی تکلف اور بناوٹ نہیں ہوتی.جس طرح پر حیوانات اور دوسرے انسان اپنے ماکولات ومشروبات اور دوسری شہوات میں
169
Page 178
لذت اُٹھاتے ہیں.اس سے بہت بڑھ چڑھ کر وہ مومن مشتقی نماز میں لذت پاتا ہے.اس
لئے نماز کو خوب سنوار سنوار کر پڑھنا چاہئے.نما ز ساری ترقیوں کی جڑ اور زمینہ ہے.اسی لئے کہا
گیا ہے کہ نماز مومن کا معراج ہے اس دین میں ہزاروں لاکھوں اولیاء اللہ، راست باز،
ابدال، قطب گزرے ہیں.انہوں نے یہ مدارج اور مراتب کیوں کر حاصل کئے؟ اسی نماز کے
ذریعہ سے.خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَقُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلوۃ یعنی میری
آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے اور فی الحقیقت جب انسان اس مقام اور درجہ پر پہنچتا ہے تو
اس کے لئے اکمل اتم لذت نماز ہی ہوتی ہے اور یہی معنے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس
ارشاد کے ہیں.پس کشاکش نفس سے انسان نجات پا کر اعلی مقام پر پہنچ جاتا ہے.غرض یاد رکھو کہ يُقِيمُونَ الصَّلوةَ وہ ابتدائی درجہ اور مرحلہ ہے جہاں نماز بے ذوقی اور
کشاکش سے ادا کرتا ہے لیکن اس کتاب کی ہدایت ایسے آدمی کے لئے یہ ہے کہ اس مرحلہ
سے نجات پاکر اس مقام پر جا پہنچتا ہے جہاں نما ز اس کے لئے قرۃ العین ہو جاوے.قرآن شریف کو جہاں سے شروع کیا ہے ان ترقیوں کا وعدہ کر لیا ہے جو بالطبع روح تقاضا
کرتی ہے.چنانچہ سورۃ فاتحہ میں اهْدِنَا القِيرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کی تعلیم کی اور فرمایا کہ تم یہ دُعا
کرو کہ اے اللہ ہم کو صراط مستقیم کی ہدایت فرماوہ صراط مستقیم جو ان لوگوں کی راہ ہے جن پر
تیرے انعام واکرام ہوئے.اس دُعا کے ساتھ ہی سورۃ البقرہ کی پہلی ہی آیت میں یہ بشارت
دے دى ذلك الكتب لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ.گویا روحیں دُعا کرتی ہیں اور ساتھ ہی
قبولیت اپنا اثر دکھاتی ہے اور وہ وعدہ دعا کی قبولیت کا قرآن مجید کے نزول کی صورت میں پورا
ہوتا ہے.ایک طرف دُعا ہے اور دوسری طرف اس کا نتیجہ موجود ہے.یہ خدا تعالیٰ کا فضل اور
کرم ہے جو اس نے فرمایا مگر افسوس دنیا اس سے بے خبر اور غافل ہے اور اس سے دور رہ کر
بلاک ہورہی ہے.میں پھر کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے جو ابتدائے قرآن مجید میں متقیوں کے
صفات بیان فرمائے ہیں ان کو معمولی صفات میں رکھا ہے.لیکن جب انسان قرآن مجید پر
ایمان لا کر اسے اپنی ہدایت کے لئے دستور العمل بناتا ہے تو وہ ہدایت کے ان اعلیٰ مدارج اور
170
Page 179
مراتب کو پالیتا ہے جو ھدی للمتقین میں مقصود رکھے ہیں قرآن شریف کی اس علت غائی
کے تصور سے ایسی لذت اور سرور آتا ہے کہ الفاظ میں ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے کیونکہ اس
سے خدا تعالیٰ کے خاص فضل اور قرآن مجید کے کمال کا پتہ لگتا ہے.پھر متقی کی ایک اور علامت بیان فرمائی و مما رَزَقُتُهُمْ يُنْفِقُونَ یعنی جو کچھ ہم نے
ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں.یہ ابتدائی حالت ہوتی ہے اور اس میں سب کے
سب شریک ہیں کیونکہ عام طور پر یہ فطرت انسانی کا ایک تقاضا ہے کہ اگر کوئی سائل اس کے
پاس آجاوے تو کچھ نہ کچھ اسے ضرور دے دیتا ہے گھر میں دس روٹیاں موجود ہوں اور کسی سائل
نے آ کر صدا کی تو ایک روٹی اس کو بھی دے دے گا یہ امر زیر ہدایت نہیں ہے بلکہ فطرت کا
ایک طبعی خاصہ ہے.اور یہ بھی یادر ہے کہ یہاں مما رَزَقُنُهُمْ يُنْفِقُونَ عام ہے اس سے کوئی
خاص ثے روپیہ پیسہ یا روٹی کپڑا مراد نہیں ہے بلکہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے اس میں
سے کچھ نہ کچھ خرچ کرتے رہتے ہیں.انفاق دو قسم کا ہوتا ہے ایک فطرتی دوسرازیر اثر نبوت.فطرتی تو وہی ہے جیسا کہ میں
نے ابھی بیان کیا ہے کہ تم میں سے کون ہے اگر کوئی قیدی یا بھوکا آدمی جو کئی روز سے بھوکا ہو
یاننگا ہو ، آ کر سوال کرے اور تم اسے کچھ نہ کچھ دے نہ دو.کیونکہ یہ امر فطرت میں داخل ہے اور
یہ بھی میں نے بتادیا ہے کہ بنا رزقنهم روپیہ پیسہ سے مخصوص نہیں خواہ جسمانی ہو یا علمی سب
مِمَّا رَزَقُلهُمْ
اس میں داخل ہے.جو علم سے دیتا ہے وہ بھی اسی کے ماتحت ہے، مال سے دیتا ہے وہ بھی
داخل ہے، طبیب ہے وہ بھی داخل ہے مگر بموجب منشاء هُدًى لِلْمُتَّقِينَ ابھی تک اس مقام
تک نہیں پہنچا جہاں قرآن شریف اسے لے جانا چاہتا ہے اور وہ وہ مقام ہے کہ انسان اپنی
زندگی ہی خدا تعالیٰ کے لئے وقف کر دے اور یہ یہی وقف کہلاتا ہے.اس حالت اور مقام پر جب ایک شخص پہنچتا ہے تو اس میں بھکا رہتا ہی نہیں کیونکہ جب تک
وہ مینا کی حد کے اندر ہے اس وقت تک وہ ناقص ہے اور اس علت غائی تک نہیں پہنچا جو
قرآن مجید کی ہے لیکن کامل اسی وقت ہوتا ہے جب یہ حد نہ رہے اور اس کا وجود اس کا ہر فعل ہر.171
Page 180
حرکت و سکون محض اللہ تعالیٰ کے حکم اور اؤن کے ماتحت بنی نوع کی بھلائی کے لئے وقف
ہو.دوسرے لفظوں میں یہ کہو کہ مِمَّا رَزَقْتُهُم يُنفِقُونَ کا کمال یہی ہے جو هُدًى لِلْمُتَّقِينَ
کے منشاء کے موافق ہے.الحکم نمبر 3 جلد 10 مؤرخہ 24 جنوری 1906 صفحہ 4-5)
اس کے بعد ایک اور صفت متقیوں کی بیان کی یعنی وہ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ
إليك کے موافق ایمان لاتے ہیں اور ایسا ہی جو کچھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اللہ
تعالی نے نازل فرمایا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں.لیکن اب سوال یہ ہے کہ اگر اتنا ہی ایمان ہے تو پھر ہدایت کیا ہے؟ وہ ہدایت یہ ہے کہ
ایسا انسان خود اس قابل ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر وحی اور الہام کا دروازہ کھولا
جاتا ہے اور وہ وحی الہی اس پر بھی اترتی ہے جس سے اس کا ایمان ترقی کر کے کامل یقین اور
معرفت کے درجہ تک پہنچ جاتا ہے اور وہ اس ترقی کو پالیتا ہے جو ہدایت کا اصل مقصود تھا.اس پر وہ انعام و اکرام ہونے لگتے ہیں جو مکالمہ الہیہ سے ملتے ہیں.یہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ
نے وحی اور الہام کے دروازہ کو بند نہیں کیا جو لوگ اس اُمت کو الہام ووحی کے انعامات سے
بے بہرہ ٹھہراتے ہیں وہ سخت غلطی پر ہیں اور قرآن شریف کے اصل مقصد کو انہوں نے سمجھا
ہی نہیں.ان کے نزدیک یہ امت وحشیوں کی طرح ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
تاثیرات اور برکات کا معاذ اللہ خاتمہ ہو چکا اور وہ خدا جو ہمیشہ سے متکلم خدا ر ہا ہے اب اس
زمانہ میں آکر خاموش ہو گیا.وہ نہیں جانتے کہ اگر مکالمه مخاطبہ نہیں تو هُدًى لِلْمُتَّقِينَ
کا مطلب ہی کیا ہوا.بغیر مکالمہ مخاطبہ کے تو اس کی ہستی پر کوئی دلیل قائم نہیں ہوسکتی اور پھر
قرآن شریف میں یہ کیوں کہا: وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا (العنكبوت 70)
اور ایک دوسرے مقام پر فرمایا : إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ
الْمَلبِكَةُ إِلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا (لحم السجدة (31) یعنی جن لوگوں نے اپنے قول اور فعل سے
بتا دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر انہوں نے استقامت دکھائی ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا
172
Page 181
ہے.اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ فرشتوں کا نزول ہوا اور مخاطبہ نہ ہو.نہیں بلکہ وہ انہیں بشارتیں
دیتے ہیں.یہی تو اسلام کی خوبی اور کمال ہے جو دوسرے مذاہب کو حاصل نہیں
ہے.استقامت بہت مشکل چیز ہے یعنی خواہ ان پر زلزلے آئیں فتنے آئیں وہ ہر قسم کی
مصیبت اور دکھ میں ڈالے جاویں مگر ان کی استقامت میں فرق نہیں آتا.ان کا اخلاص اور
وفاداری پہلے سے زیادہ ہوتی ہے ایسے لوگ اس قابل ہوتے ہیں کہ ان پر خدا کے فرشتے
اُتریں اور انہیں بشارت دیں کہ تم کوئی غم نہ کرو.یہ یقیناً یا د رکھو کہ وحی اور الہام کے سلسلہ
کے متعلق خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں اکثر جگہ وعدے کئے ہیں اور یہ اسلام ہی سے
مخصوص ہے.ورنہ عیسائیوں کے ہاں بھی مہر لگ چکی ہے وہ اب کوئی شخص ایسا نہیں بتا سکتے
جواللہ تعالیٰ کے مخاطبہ مکالمہ سے مشرف ہو.اور ویدوں پر تو پہلے ہی سے مہر لگی ہوئی ہے ان کا
تو مذہب ہی یہی ہے کہ ویدوں کے الہام کے بعد پھر ہمیشہ کے لئے یہ سلسلہ بند ہو گیا گویا
خدا پہلے کبھی بولا تھا مگر اب وہ گونگا ہے.میں کہتا ہوں کہ اگر وہ اس وقت کلام نہیں کرتا اور
کوئی اس کے اس فیض سے بہرہ ور نہیں تو اس کا کیا ثبوت ہے کہ وہ پہلے بولتا تھا اور یا اب وہ
سنتا اور دیکھتا بھی ہے؟ مجھے افسوس ہوتا ہے جب میں مسلمانوں کے منہ سے اس قسم کے الفاظ
نکلتے سنتا ہوں کہ اب مخاطبہ مکالمہ کی نعمت کسی کو نہیں مل سکتی.یہ کیوں عیسائیوں یا آریوں کی
طرح مہر لگاتے ہیں.اگر اسلام میں یہ کمال اور خوبی نہ ہو تو پھر دوسرے مذاہب پر اسے کیا فخر
اور امتیاز حاصل ہوگا....ی سچی بات یہ ہے کہ اسلام کی روح اور اصل حقیقت تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مکالمہ اور
مخاطبہ کا شرف وہ انسان کو عطا کرتا ہے خدا تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ آسمان سے انعام و
اکرام ملتے ہیں.جب انسان اس مرتبہ اور مقام پر پہنچ جاتا ہے تو اس کی نسبت کہا جاتا ہے
أوليك على هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَبِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ یعنی یہی وہ لوگ ہیں جو کامل ترقی پاکر
اپنے رب کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے نجات پائی ہے.173
Page 182
قرآن شریف نے شروع میں ہی فرمایا هُدًى لِلْمُتَّقِينَ پس قرآن شریف کے سمجھنے اور اس
کے موافق ہدایت پانے کے لئے تقویٰ ضروری اصل ہے.ایسا ہی دوسری جگہ فرمایا: لا يمسه إِلَّا
الْمُطَهَّرُونَ (الواقعة : 80) دوسرے علوم میں یہ شرط نہیں.ریاضی، ہندسہ وہیئت وغیرہ میں
اس امر کی شرط نہیں کہ سیکھنے والا ضرور متقی اور پرہیز گار ہو بلکہ خواہ کیسا ہی فاسق و فاجر ہی ہو وہ
بھی سیکھ سکتا ہے مگر علم دین میں خشک منطقی اور فلسفی ترقی نہیں کر سکتا اور اس پر وہ حقائق
اور معارف نہیں کھل سکتے.جس کا دل خراب ہے اور تقویٰ سے حصہ نہیں رکھتا اور پھر کہتا ہے
که علوم دین اور حقائق اس کی زبان پر جاری ہوتے ہیں وہ جھوٹ بولتا ہے ہر گز ہرگز اسے دین
کے حقائق اور معارف سے حصہ نہیں ملتا بلکہ دین کے لطائف اور نکات کے لئے متقی ہونا
شرط ہے.یہ خوب یاد رکھو کہ تقویٰ تمام دینی علوم کی کنجی ہے انسان تقویٰ کے سوا ان کو نہیں سیکھ سکتا
جیسا کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا : الم - ذلِكَ الْكِتَبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ.يه كتاب
تقویٰ کرنے والوں کو ہدایت کرتی ہے اور وہ کون ہیں الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ جو غیب پر
ایمان لاتے ہیں.یعنی ابھی وہ خدا نظر نہیں آتا اور پھر نماز کو کھڑی کرتے ہیں یعنی نماز میں ابھی
پورا سرور اور ذوق پیدا نہیں ہوتا تاہم بے لطفی اور بے ذوقی اور وساوس میں ہی نماز کو قائم
کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کچھ خرچ کرتے ہیں اور جو کچھ تجھ پر یا
تجھ سے پہلے نازل کیا گیا ہے اُس پر ایمان لاتے ہیں.متقی کے ابتدائی مدارج اور صفات ہیں.حکم جلد 11 نمبر 3 مؤرخہ 24 جنوری 1907 ، صفحہ 7)
اسلام نے بہت ہی آسان راہ رکھی ہے اور وہ کشادہ راہ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے
یوں فرمایا ہے اهدِنَا القِرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ اب اللہ تعالیٰ نے جو یہ دعا سکھائی ہے تو اس طور
پر نہیں کہ دُعا تو سکھا دی لیکن سامان کچھ نہیں.بلکہ جہاں دُعا سکھائی ہے وہاں سب کچھ موجود
ہے چنانچہ انگلی سورت میں اس قبولیت کا اشارہ ہے جہاں فرمایا.ذلِكَ الْكِتَبُ لَا رَيْبَ فِيهِ
174
Page 183
هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ.یہ ایسی دعوت ہے کہ دعوت کا سامان پہلے سے طیار ہے.الحكم جلد 9 نمبر 11 مؤرخہ 31 مارچ 1905 ، صفح؟؟؟)
سورۃ بقرہ کے شروع میں ہی جو ھدی للمتقین کہا گیا تو گویا خدا تعالیٰ نے دینے کی
تیاری کی یعنی یہ کتاب متقی کو کمال تک پہنچانے کا وعدہ کرتی ہے.سواس کے معنی یہ ہیں کہ یہ
کتاب اُن کے لئے نافع ہے جو پر ہیز کرنے اور نصیحت سننے کو تیار ہو.اس درجہ کا متقی وہ
ہے جو ٹھٹی بالطبع ہو کر حق کی بات سنے کو تیار ہو.جیسے جب کوئی مسلمان ہوتا ہے تو وہ متقی بنتا
ہے.جب کسی غیر مذہب کے اچھے دن آئے تو اُس میں انتقا پیدا ہوا.محجب، غرور، پندار دُور
ہوا.یہ تمام روکیں تھیں جوڈور ہوگئیں.ان کے دُور ہونے سے تاریک گھر کی کھڑ کی کھل گئی اور
شعاعیں اندر داخل ہوگئیں.یہ جو فرمایا کہ یہ کتاب مُتَّقِین کی ہدایت ہے.یعنی هدی
لِلْمُتَّقِينَ تو اتقاء جو افتعال کے باب پر ہے اور یہ باب تکلف کے لئے آیا کرتا ہے یعنی
اس میں اشارہ ہے کہ جس قدر یہاں ہم تقویٰ چاہتے ہیں، وہ تکلف سے خالی نہیں جس کی حفاظت
کے لئے اس کتاب میں ہدایات ہیں.گویا متقی کو نیکی کرنے میں تکلیف سے کام لینا پڑتا
ہے.جب یہ درجہ گزرجاتا ہے تو سالک عبد صالح ہو جاتا ہے گو یا تکلیف کا رنگ دور ہوا.اور
صالح نے طبعاً و فطرتا نیکی شروع کی وہ ایک قسم کے دارالامان میں ہے جس کو کوئی خطرہ نہیں.اب گل جنگ اپنے نفسانی جذبات کے برخلاف ختم ہو چکی اور وہ امن میں آ گیا اور ہر ایک قسم
کے خطرات سے پاک ہو گیا.اسی امر کی طرف ہمارے بادی کامل نے اشارہ کیا ہے فرمایا کہ
ہر ایک کے ساتھ شیطان ہوتا ہے لیکن میرا شیطان مسلم ہو گیا ہے.سومشقی کو ہمیشہ شیطان کے
مقابل جنگ ہے لیکن جب وہ صالح ہو جاتا ہے تو گل جنگیں بھی ختم ہو جاتی ہیں....ایک متقی تو اپنے نفس اتارہ کے برخلاف جنگ کر کے اپنے خیال کو چھپاتا ہے اور خفیہ
رکھتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس خفیہ خیال کو ہمیشہ ظاہر کر دیتا ہے.جیسا ایک بدمعاش کسی بد چلنی کا
مرتکب ہو کر خفیہ رہنا چاہتا ہے.اسی طرح ایک متقی چھپ کر نماز پڑھتا ہے اور ڈرتا ہے کہ
کوئی اس کو نہ دیکھ لے.سچا متقی ایک قسم کا ستر چاہتا ہے.تقویٰ کے مراتب بہت
175
Page 184
ہیں.لیکن بہر حال تقویٰ کے لئے تکلف ہے.اور متقی حالتِ جنگ میں ہے اور صالح
اُس جنگ سے باہر ہے.رپورٹ جلسہ سالانہ 1897 ، صفحہ 39 تا 41)
تقویٰ سے سب شے ہے.قرآن نے ابتدا اسی سے کی ہے إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ
نَسْتَعِينُ سے بھی مُراد تقویٰ ہے کہ انسان اگر چہ عمل کرتا ہے مگر خوف سے جرات نہیں کرتا کہ
اسے اپنی طرف منسوب کرے اور اُسے خدا کی استعانت سے خیال کرتا ہے اور پھر اُسی سے
آئندہ کے لئے استعانت طلب کرتا ہے.پھر دوسری سورت بھی هُدًى لِلْمُتَّقِينَ سے شروع
ہوتی ہے.نماز روزہ زکوۃ وغیرہ سب اسی وقت قبول ہوتا ہے جب انسان متقی ہو.اُس وقت خدا
تمام داعی گناہ کے اٹھا دیتا ہے.بیوی کی ضرورت ہو تو بیوی دیتا ہے.دوا کی ضرورت ہو تو
دوا دیتا ہے.جس شے کی حاجت ہو وہ دیتا ہے اور ایسے مقام سے روزی دیتا ہے کہ اُسے خبر
نہیں ہوتی.البدر جلد 1 نمبر 7 مؤرخہ 12 دسمبر 1902 صفحہ 51)
تقویٰ اختیار کرو.تقویٰ ہر چیز کی جڑ ہے.تقویٰ کے معنی ہیں ہر ایک بار یک
در باریک رگ گناہ سے بچنا.تقویٰ اس کو کہتے ہیں کہ جس امر میں بدی کا شبہ بھی ہو اُس سے بھی
کنارہ کرے.الحکم جلد 5 نمبر 29 مؤرخہ 10 اگست 1901 صفحہ 3)
اللہ تعالیٰ کے خوف سے اور اس کو راضی کرنے کے لئے جو شخص ہر ایک بدی سے بچتا
ہے اس کو متقی کہتے ہیں....اللہ تعالیٰ تو متقی کے لئے وعدہ کرتا ہے کہ مَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَل
له مخرجًا (الطلاق 3) یعنی جو اللہ تعالیٰ کے لئے تقویٰ اختیار کرتا ہے تو ہر مشکل سے اللہ تعالیٰ
اس کو رہائی دے دیتا ہے.لوگوں نے تقویٰ کے چھوڑنے کے لئے طرح طرح کے بہانے بنا
رکھے ہیں.بعض کہتے ہیں کہ جھوٹ بولے بغیر ہمارے کاروبار نہیں چل سکتے اور دوسرے لوگوں
پر الزام لگاتے ہیں کہ اگر سچ کہا جائے تو وہ لوگ ہم پر اعتبار نہیں کرتے.پھر بعض لوگ ایسے
176
Page 185
ہیں جو کہتے ہیں کہ سُود لینے کے بغیر ہمارا گزارہ نہیں ہو سکتا.ایسے لوگ کیونکر متقی کہلا سکتے ہیں؟
خدا تعالیٰ تو وعدہ کرتا ہے کہ میں متقی کو ہر ایک مشکل سے نکالوں گا اور ایسے طور سے رزق دوں گا
جو گمان اور وہم میں بھی نہ آ سکے.اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے جولوگ ہماری کتاب پر عمل کریں گے
ان کو ہر طرف سے اوپر سے اور نیچے (سے) رزق دوں گا.پھر فرمایا ہے کہ فی السَّمَاءِ
رِزْقُكُمْ (الذاریات (23) جس کا مطلب یہی ہے کہ رزق تمہارا تمہاری اپنی محنتوں اور
کوششوں اور منصوبوں سے وابستہ نہیں وہ اس سے بالا تر ہے.یہ لوگ ان وعدوں سے فائدہ
نہیں اُٹھاتے اور تقویٰ اختیار نہیں کرتے جو شخص تقویٰ اختیار نہیں کرتا وہ معاصی میں غرق رہتا
ہے اور بہت ساری رکاوٹیں اس کی راہ میں حائل ہو جاتی ہیں.( البدر جلد 3 نمبر 25 مؤرخہ یکم جولائی 1904 ، صفحہ 5)
الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلوةَ وَ مِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنْفِقُوْنَ ایمان لانے پر
ثواب اسی وجہ سے ملتا ہے کہ ایمان لانے والا چند قرائن صدق کے لحاظ سے ایسی باتوں کو قبول
کر لیتا ہے کہ وہ ہنوز مخفی ہیں جیسا کہ اللہ جل شانہ نے مومنوں کی تعریف قرآن کریم میں
فرمائی ہے کہ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ یعنی ایسی بات کو مان لیتے ہیں کہ وہ ہنوز در پردہ غیب ہے
جیسا کہ صحابہ کرام نے ہمارے سید و مولی صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا اور کسی نے نشان نہ مانگا اور
کوئی ثبوت طلب نہ کیا اور گو بعد اسکے اپنے وقت پر بارش کی طرح نشان بر سے اور معجزات
ظاہر ہوئے لیکن صحابہ کرام ایمان لانے میں معجزات کے محتاج نہیں ہوئے اور اگر وہ معجزات
کے دیکھنے پر ایمان موقوف رکھتے تو ایک ذرہ بزرگی ان کی ثابت نہ ہوتی اور عوام میں سے شمار
کئے جاتے اور خدائے تعالیٰ کے مقبول اور پیارے بندوں میں داخل نہ ہو سکتے کیونکہ جن جن لوگوں
نے نشان مانگا خدائے تعالیٰ نے ان پر عتاب ظاہر کیا اور در حقیقت ان کا انجام اچھا نہ ہوا اور
اکثر وہ بے ایمانی کی حالت میں ہی مرے.غرض خدا تعالیٰ کی تمام کتابوں سے ثابت ہوتا ہے
که نشان مانگنا کسی قوم کے لئے مبارک نہیں ہوا اور جس نے نشان مانگا وہی تباہ ہوا.انجیل
میں بھی حضرت مسیح فرماتے ہیں کہ اس وقت کے حرام کار مجھ سے نشان مانگتے ہیں ان کو کوئی
177
Page 186
نشان دیا نہیں جائے گا.میں پہلے بھی لکھ چکا ہوں کہ بالطبع ہر ایک شخص کے دل میں اس جگہ یہ
سوال پیدا ہوگا کہ بغیر کسی نشان کے حق اور باطل میں انسان کیوں کر فرق کر سکتا ہے اور اگر بغیر
نشان دیکھنے کے کسی کو منجانب اللہ قبول کیا جائے تو ممکن ہے کہ اس قبول کرنے میں دھوکا
ہو.اس کا جواب وہی ہے جو میں لکھ چکا ہوں کہ خدائے تعالیٰ نے ایمان کا ثواب اکثر اسی امر
سے مشروط کر رکھا ہے کہ نشان دیکھنے سے پہلے ایمان ہو اور حق اور باطل میں فرق کرنے کے
لئے یہ کافی ہے کہ چند قرائن جو وجہ تصدیق ہوسکیں اپنے ہاتھ میں ہوں اور تصدیق کا پلہ تکذیب
کے پلّہ سے بھاری ہو.مثلاً حضرت صدیق اکبر ابو بکر رضی اللہ عنہ جو آ نحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
پر ایمان لائے تو انہوں نے کوئی معجزہ طلب نہیں کیا اور جب پوچھا گیا کہ کیوں ایمان لائے تو
بیان کیا کہ میرے پر محمدصلی اللہ علیہ وسلم کا امین ہونا ثابت ہے اور میں یقین رکھتا ہوں کہ انہوں
نے
کبھی کسی انسان کی نسبت بھی جھوٹ کو استعمال نہیں کیا چہ جائیکہ خدا تعالیٰ پر جھوٹ باندھیں!
ایسا ہی اپنے اپنے مذاق پر ہر یک صحابی ایک، ایک اخلاقی یا تعلیمی فضیلت آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کی دیکھ کر اور اپنی نظیر دقیق سے اس کو وجہ صداقت ٹھہرا کر ایمان لائے تھے اور ان
میں سے کسی نے بھی نشان نہیں مانگا تھا اور کاذب اور صادق میں فرق کرنے کے لئے ان کی
نگاہوں میں یہ کافی تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تقویٰ کے اعلیٰ مراتب پر ہیں.اپنے منصب
کے اظہار میں بڑی شجاعت اور استقامت رکھتے ہیں اور جس تعلیم کو لائے ہیں وہ دوسری سب
تعلیموں سے صاف تر اور پاک تر اور سراسر نور ہے اور تمام اخلاق حمیدہ میں.سابے نظیر ہیں اور لہی
جوش ان میں اعلیٰ درجہ کے پائے جاتے ہیں اور صداقت ان کے چہرہ پر برس رہی ہے.پس
انہیں باتوں کو دیکھ کر انہوں نے قبول کر لیا کہ وہ در حقیقت خدائے تعالیٰ کی طرف سے ہیں.اس جگہ یہ نہ سمجھا جائے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات ظاہر نہیں ہوئے بلکہ تمام انبیاء
سے زیادہ ظاہر ہوئے لیکن عادت اللہ اسی طرح پر جاری ہے کہ اوائل میں کھلے کھلے معجزات اور
نشان مخفی رہتے ہیں تا صادقوں کا صدق اور کا ذبوں کا کذب پرکھا جائے.یہ زمانہ ابتلا کا ہوتا ہے
اور اس میں کوئی کھلا کھلا نشان ظاہر نہیں ہوتا.پھر جب ایک گروہ صافی دلوں کا اپنی نظر دقیق
178
Page 187
سے ایمان لے آتا ہے اور عوام کالانعام باقی رہ جاتے ہیں تو ان پر حجت پوری کرنے کے لئے
یا ان پر عذاب نازل کرنے کیلئے نشان ظاہر ہوتے ہیں مگر ان نشانوں سے وہی لوگ فائدہ
اٹھاتے ہیں جو پہلے ایمان لاچکے تھے اور بعد میں ایمان لانے والے بہت کم ہوتے ہیں کیونکہ
ہر روزہ تکذیب سے ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں اور اپنی مشہور کردہ راؤں کو وہ بدل نہیں سکتے
آخر اسی کفر اور انکار میں واصل جہنم ہوتے ہیں.مجھے دلی خواہش ہے اور میں دُعا کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بات سمجھ آجاوے کہ در حقیقت ایمان
کے مفہوم کے لئے یہ بات ضروری ہے کہ پوشیدہ چیزوں کو مان لیا جائے اور جب ایک چیز کی
حقیقت ہر طرح سے کھل جائے یا ایک وافر حصہ اس کا کھل جائے تو پھر اس کا مان لینا ایمان
میں داخل نہیں.مثلاً اب جو دن کا وقت ہے اگر میں یہ کہوں کہ میں اس بات پر ایمان لاتا ہوں
کہ اب دن ہے رات نہیں ہے تو میرے اس ماننے میں کیا خوبی ہوگی اور اس ماننے میں مجھے
دوسروں پر کیا زیادت ہے؟ سعید آدمی کی پہلی نشانی یہی ہے کہ اس بابرکت بات کو سمجھ لے کہ
ایمان کس چیز کو کہا جاتا ہے کیونکہ جس قدر ابتدائے دنیا سے لوگ انبیاء کی مخالفت کرتے
آئے ہیں ان کی عقلوں پر یہی پردہ پڑا ہوا تھا کہ وہ ایمان کی حقیقت کو نہیں سمجھتے تھے اور چاہتے
تھے کہ جب تک دوسرے امور مشہورہ محسوسہ کی طرح انبیاء کی نبوت اور ان کی تعلیم کھل نہ جائے
تب تک قبول کرنا مناسب نہیں اور وہ بیوقوف یہ خیال نہیں کرتے تھے کہ کھلی ہوئی چیز کو ماننا
ایمان میں کیوں کر داخل ہوگا وہ تو ہندسہ اور حساب کی طرح ایک علم ہوا نہ کہ ایمان.پس یہی
حجاب تھا کہ جس کی وجہ سے ابو جہل اور ابولہب وغیرہ اوائل میں ایمان لانے سے محروم رہے
اور پھر جب اپنی تکذیب میں پختہ ہو گئے اور مخالفانہ راؤں پر اصرار کر چکے اس وقت آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے کھلے کھلے نشان ظاہر ہوئے تب انہوں نے کہا کہ اب قبول
کرنے سے مرنا بہتر ہے.غرض نظر دقیق سے صادق کے صدق کو شناخت کرنا سعیدوں کا کام
ہے اور نشان طلب کرنا نہایت منحوس طریق اور اشقیا کا شیوہ ہے جس کی وجہ سے کروڑ با منکر
ہیزم جہنم ہو چکے ہیں.خدائے تعالیٰ اپنی سنت کو نہیں بدلتا وہ جیسا کہ اس نے فرما دیا ہے انہی
179
Page 188
کے ایمان کو ایمان سمجھتا ہے جو زیادہ ضد نہیں کرتے اور قرائن مرجحہ کو دیکھ کر اور علامات صدق
پا کر صادق کو قبول کر لیتے ہیں اور صادق کا کلام صادق کی راستبازی صادق کی استقامت اور خود
صادق کا منہ ان کے نزدیک اس کے صدق پر گواہ ہوتا ہے.مبارک وہ جن کو مردم شناسی کی
عقل دی جاتی ہے.( آئینہ کمالات اسلام ، روحانی خزائن جلد 5 فحہ 336 تا339)
متقی کی حالت میں چونکہ رویت باری تعالیٰ اور مکالمات و مکاشفات کے مراتب
حاصل نہیں ہوتے.اس لئے اس کو اول ایمان بالغیب ہی کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ تکلف
کے طور پر ایمانی درجہ ہوتا ہے کیونکہ قرائن قویہ کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی ہستی پر ایمان لاتا ہے جو
بَيْنَ الشَّاكِ وَالْيَقِينِ ہوتا ہے.ی ایمان بالغیب متقی کے پہلے درجہ کی حالت اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی وقعت رکھتی
ہے.حدیث صحیح میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ جانتے ہو
سب سے بڑھ کر ایمان کس کا ہے.صحابہ نے عرض کی کہ حضور آپ کا ہی ہے.آپ نے فرمایا
کہ میرا کس طرح ہو سکتا ہے میں تو ہر روز جبریل کو دیکھتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نشانات کو ہر وقت
دیکھتا ہوں.پھر صحابہ نے عرض کی کہ کیا ہمارا ایمان؟ پھر آپ نے فرمایا کہ تمہارا ایمان کس
طرح تم بھی تو نشانات دیکھتے ہو.آخر خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جولوگ صد با
سال کے میرے بعد آئیں گے ان کا ایمان عجیب ہے کیونکہ وہ کوئی بھی ایسا نشان نہیں دیکھتے
جیسے تم دیکھتے ہو مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں.غرض خدا تعالیٰ متقی کو اگر وہ اسی ابتدائی
درجہ میں مرجاوے تو اسی زمرہ میں داخل کر لیتا ہے اور اسی دفتر میں اس کا نام لکھ دیتا ہے
باوجود یکہ وہ مکالمات اور مخاطبات الہیہ کو نہیں جانتا اور اس لذت اور نعمت سے ابھی اس نے
کچھ بھی نہیں پایا لیکن پھر بھی وہ ایسی قوت دکھاتا ہے کہ نہ صرف اللہ تعالیٰ پر ایمان ہی رکھتا
ہے بلکہ اس ایمان کو اپنے عمل سے بھی ثابت کرتا ہے یعنی يُقِيمُونَ الصَّلوةَ
تقویٰ کی اس حالت میں نمازوں میں بھی وسوسے ہوتے ہیں اور قسم قسم کے وہم اور شکوک
180
Page 189
پیدا ہو کر خیالات کو پراگندہ کرتے ہیں، باوجود اس کے بھی وہ نما زنہیں چھوڑتے اور نہیں تھکتے
اور ہارتے.بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ چند روز نماز پڑھی اور ظنون فاسدہ اور خیالات
پراگندہ دل میں گزرنے لگے.نماز چھوڑ دی اور ہار کر بیٹھ رہے مگر متقی اپنی ہمت نہیں ہارتا وہ
نماز کو کھڑی کرتا نما زگری پڑتی ہے وہ بار بارا سے کھڑی کرتا ہے.تقویٰ کی حالت میں دو زمانے متقی پر آتے ہیں.ایک ابتلا کا زمانہ دوسرا اصطفا کا زمانہ.ابتلا کا زمانہ اس لئے آتا ہے کہ تا تمہیں اپنی قدر و منزلت اور قابلیت کا پتہ مل جائے اور یہ ظاہر
ہو جائے کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر راستبازوں کی طرح ایمان لاتا ہے.اس لئے کبھی اس کو
وہم اور شکوک آ کر پریشان دل کرتے ہیں کبھی کبھی خدا تعالیٰ ہی کی ذات پر اعتراض اور وہم
پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں.صادق مومن کو اس مقام پر ڈرنا اور گھبرانا نہ چاہئے بلکہ آگے
ہی قدم رکھے.کسی نے کہا ہے :
عشق اول سرکش و خونی بود تا گریز دہر کہ بیرونی بود
شیطان پلید کا کام ہے کہ وہ راضی نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے منکر نہ
کرالے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے روگردان نہ کرلے.وہ وساوس پر
وساوس ڈالتا رہتا ہے لاکھوں کروڑوں انسان انہیں وسوسوں میں مبتلا ہو کر ہلاک ہورہے ہیں
اور کہتے ہیں کہ اب کر لیں پھر دیکھا جائے گا.باوجود اس کے کہ انسان کو اس بات کا علم نہیں کہ
ایک سانس کے بعد دوسرا سانس آئے گا بھی یا نہیں لیکن شیطان ایسا دلیر کرتا ہے کہ وہ بڑی
بڑی جھوٹی امیدیں دیتا اور سبز باغ دکھاتا ہے.شیطان کا یہ پہلا سبق ہوتا ہے مگرمتقی بہادر ہوتا
ہے اس کو ایک جرات دی جاتی ہے کہ وہ ہر وسوسہ کا مقابلہ کرتا ہے اس لئے يُقِيمُونَ الصَّلوةَ
فرمایا یعنی اس درجہ میں وہ ہارتے اور تھکتے نہیں اور ابتدا میں انس اور ذوق اور شوق کا نہ ہونا اُن کو
بے دل نہیں کرتا وہ اسی بے ذوقی اور بے لطفی میں بھی نماز پڑھتے رہتے ہیں یہاں تک کہ سب
وساوس اور اوہام دور ہو جاتے ہیں.شیطان کو شکست ملتی اور مومن کامیاب ہو جاتا ہے.غرض
منتقی کا یہ زمانہ ستی کا زمانہ نہیں ہوتا بلکہ میدان میں کھڑے رہنے کا زمانہ ہوتا ہے.وساوس کا
181
Page 190
پوری مردانگی سے مقابلہ کرے.حکم جلد 5 نمبر 6 مؤرخہ 17 فروری 1901 ، صفحہ 1 تا 2)
تقومی...کسی قدر تکلف کو چاہتا ہے.اسی لئے تو فرمایا کہ هُدًى لِلْمُتَّقِيْنَ الَّذِينَ
يُؤْمِنُونَ بِالْغَیب.اس میں ایک تکلف ہے.مشاہدہ کے مقابل ایمان بالغیب لانا ایک قسم کے
تکلف کو چاہتا ہے.سو متقی کے لئے ایک حد تک تکلف ہے کیونکہ جب وہ صالح کا درجہ حاصل
کرتا ہے تو پھر غیب اس کے لئے غیب نہیں رہتا کیونکہ صالح کے اندر سے ایک نہر نکلتی ہے جو
اس میں سے نکل کر خدا تک پہنچتی ہے.وہ خدا اور اس کی محبت کو اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے.کہ من
كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أعمى (بنی اسرائیل (73).اسی سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب تک
انسان پوری روشنی اسی جہان میں نہ حاصل کر لے وہ کبھی خدا کا منہ نہ دیکھے گا سو تقی کا کام یہی ہے کہ
وہ ہمیشہ ایسے سرمے طیار کرتا رہے جس سے اس کا روحانی نزول الماء دور ہو جاوے.اب اس
سے ظاہر ہے کہ متقی شروع میں اندھا ہوتا ہے مختلف کوششوں اور تزکیوں سے وہ نور حاصل
کرتا ہے.سو جب سوجا کھا ہو گیا اور صالح بن گیا پھر ایمان بالغیب نہ رہا اور تکلف بھی ختم ہو گیا
جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو برأَي الْعَيْنِ اسی عالم میں بہشت و دوزخ وغیرہ سب کچھ
مشاہدہ کرایا گیا جو متقی کو ایک ایمان بالغیب کے رنگ میں ماننا پڑتا ہے وہ تمام آپ کے مشاہدہ
میں آ گیا.سو اس آیت میں اشارہ ہے کہ متقی اگر چہ اندھا ہے اور تکلف کی تکلیف میں ہے.لیکن
صالح ایک دارالامان میں آ گیا ہے اور اُس کا نفس نفس مطمئنہ ہو گیا ہے.متقی اپنے اندر ایمان
بالغیب کی کیفیت رکھتا ہے.وہ اندھا دھند طریق سے چلتا ہے اُس کو کچھ خبر نہیں.ہر ایک بات پر
اُس کا ایمان بالغیب ہے.یہی اُس کا صدق ہے اور اس صدق کے مقابل خدا کا وعدہ ہے کہ وہ فلاح
پائے گا أُولَبِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
اس کے بعد متقی کی شان میں آیا ہے.وَيُقِيمُونَ الصَّلوةَ یعنی وہ نماز کو کھڑی کرتا ہے.یہاں لفظ کھڑی کرنے کا آیا ہے، یہ بھی اُس تکلف کی طرف اشارہ کرتا ہے جو متقی کا خاصہ ہے.یعنی جب وہ نماز شروع کرتا ہے تو طرح طرح کے وساوس کا اُسے مقابلہ ہے جن کے باعث
182
Page 191
اس کی نماز گویا بار بار گرتی پڑتی ہے جس کو اُس نے کھڑا کرنا ہے.جب اُس نے الله اكبر
کہا تو ایک ہجوم وساوس ہے جو اس کے حضور قلب میں تفرق ڈال رہا ہے.وہ ان سے
کہیں
کا کہیں پہنچ جاتا ہے، پریشان ہوتا ہے.ہر چند حضور و ذوق کے لئے لڑتا مرتا ہے لیکن نما ز جو
گری پڑتی ہے بڑی جانکنی سے اسے کھڑا کرنے کے فکر میں ہے.بار بار إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ
نستعین کہہ کر نماز کے قائم کرنے کے لئے دُعا مانگتا ہے اور ایسے الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کی
ہدایت چاہتا ہے جس سے اس کی نماز کھڑی ہو جاوے.ان وساوس کے مقابل میں متقی ایک بچہ کی
طرح ہے جو خدا کے آگے گڑ گڑاتا ہے روتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اخلد الی الْأَرْضِ ہورہا ہوں.سو
یہی وہ جنگ ہے جو تقی کو نماز میں نفس کے ساتھ کرنا ہے اور اسی پر ثواب مترتب ہوگا.بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نماز میں وساوس کو فی الفور دور کرنا چاہتے ہیں حالانکہ
وَيُقِيمُونَ الصَّلوة کی منشاء کچھ اور ہے.کیا خدا نہیں جانتا؟ حضرت شیخ عبدالقادر گیلانی
( رحمتہ اللہ علیہ ) کا قول ہے کہ ثواب اس وقت تک ہے جب تک مجاہدات ہیں اور جب
مجاہدات ختم ہوئے تو ثواب ساقط ہو جاتا ہے.گو یا صوم وصلوٰۃ اُس وقت تک اعمال ہیں
جب تک ایک جدو جہد سے وساوس کا مقابلہ ہے لیکن جب اُن میں ایک اعلیٰ درجہ پیدا ہو گیا اور
صاحب صوم وصلوٰۃ تقویٰ کے تکلف سے بچ کر صلاحیت سے رنگین ہو گیا تو اب صوم وصلوۃ اعمال
نہیں رہے.اس موقعہ پر انہوں نے سوال کیا ہے کہ کیا اب نماز معاف ہو جاتی ہے؟ کیونکہ
ثواب تو اُس وقت تک تھا جس وقت تک تکلف کرنا پڑتا تھا.سو بات یہ ہے کہ نماز اب عمل
نہیں بلکہ ایک انعام ہے.یہ نما ز اس کی ایک غذا ہے.اس کے لئے قرة العین ہے.یہ
گو یا نقد بہشت ہے.مقابل میں وہ لوگ جو مجاہدات میں ہیں وہ کشتی کر رہے ہیں اور یہ نجات
پاچکا ہے.سو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا سلوک جب ختم ہوا.تو اُس کے مصائب بھی ختم
ہو گئے.مثلاً ایک مخنث اگر کہے کہ وہ کبھی کسی عورت کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا تو وہ
کونسی نعمت یا ثواب کا مستحق ہے اس میں تو صفت بدنظری ہے ہی نہیں لیکن ایک مرد صاحب
رجولیت اگر ایسا کرے تو ثواب پاوے گا.اسی طرح انسان کو ہزاروں مقامات طے کرنے
183
Page 192
پڑتے ہیں.بعض بعض امور میں اس کی مشاقی اُس کو قادر کر دیتی ہے.نفس کے ساتھ اُس کی
مصالحت ہو گئی.اب وہ ایک بہشت میں ہے لیکن وہ پہلا سا ثواب نہیں رہے گا.وہ ایک
تجارت کر چکا ہے جس کا اب وہ نفع اٹھا رہا ہے لیکن پہلا رنگ نہ رہے گا.انسان میں ایک
فعل تکلف سے کرتے کرتے اُس میں طبعیت کا رنگ پیدا ہو جاتا ہے.ایک شخص جوطبعی طور
سے لذت پاتا ہے وہ اس قابل نہیں رہتا کہ اس کام سے ہٹایا جاوے.وہ طبعاً یہاں سے ہٹ
نہیں سکتا.سو اتقا اور تقویٰ کی حد تک پورا انکشاف نہیں ہوتا وہ ایک قسم کا دعویٰ ہے.اس کے بعد متقی کی شان میں وَمِمَّا رَزَقُنُهُم يُنفِقُونَ آیا ہے.یہاں متقی کے لئے ہما کا
لفظ استعمال کیا.کیونکہ اس وقت وہ ایک اعمی کی حالت میں ہے اس لئے کہ جو کچھ خدا نے اُس
کو دیا اُس میں سے کچھ خدا کے نام کا دیا.حق یہ ہے کہ اگر وہ آنکھ رکھتا تو دیکھ لیتا کہ اس کا
کچھ بھی نہیں سب خدا کا ہی ہے.یہ ایک حجاب تھا.جو اتقا میں لازمی ہے.اس حالت اتقا
کے تقاضے نے متقی سے خدا کے دیئے میں سے کچھ دلوایا.رسول اکرم نے حضرت عائشہؓ سے
ایام وفات میں دریافت فرمایا کہ گھر میں کچھ ہے.معلوم ہوا کہ ایک دینار تھا.فرمایا کہ یہ
سیرت یگانگت سے بعید ہے کہ ایک چیز بھی اپنے پاس رکھی جاوے.رسول اکرم صلی اللہ
علیہ وسلم اتقا کے درجہ سے گزر کر صلاحیت تک پہنچ چکے تھے.اس لئے میگا اُن کی شان میں نہ
آیا.کیونکہ وہ اندھا ہے جس نے کچھ اپنے پاس رکھا اور کچھ خدا کو دیا لیکن یہ لازمہ منتقی تھا
کیونکہ خدا کے راہ (میں) دینے میں بھی اُسے نفس کے ساتھ جنگ تھا جس کا نتیجہ یہ تھا کہ کچھ
دیا اور کچھ رکھا.وہاں رسول اکرم نے سب خدا کو دیا اور اپنے لئے کچھ نہ رکھا.وَما رَزَقْلُهُمْ يُنْفِقُونَ.رزق سے مُراد صرف مال نہیں بلکہ جو کچھ اُن کو عطا ہوا ، علم ،
حکمت، طبابت، یہ (سب) کچھ رزق میں ہی شامل ہے.اُس کو اسی میں سے خدا کی راہ میں
بھی خرچ کرتا ہے.انسان نے اس راہ میں بتدریج اور زینہ بہ زینہ ترقی کرنا ہے.اگر انجیل کی
طرح یہ تعلیم ہوتی کہ گال پر ایک طمانچہ کھا کر دوسرے طمانچہ کے لئے گال آگے رکھ دی
جاوے.یا سب کچھ دے دیا جاوے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ مسلمان بھی عیسائیوں کی طرح تعلیم
184
Page 193
کے ناممکن التعمیل ہونے کے باعث ثواب سے محروم رہتے.لیکن قرآن تو حسب فطرت
انسانی آہستہ آہستہ ترقی کراتا ہے.انجیل کی مثال تو اُس لڑکے کی ہے جو مکتب میں داخل
ہوتے ہی بڑی مشکل مکتب کی کتاب پڑھنے کے لئے مجبور کیا گیا ہے.اللہ تعالیٰ حکیم ہے،
اُس کی حکمت کا یہی تقاضا ہونا چاہئے تھا کہ تدریج کے ساتھ تعلیم کی تکمیل ہو.رپورٹ جلسہ سالانہ 1897، صفحہ 44 -47)
يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلوةَ وَ ما رَزَقُلهُمْ يُنفِقُونَ.یاد رکھو اتقا تین قسم کا ہوتا ہے.پہلی قسم ایفا کی علمی رنگ رکھتی ہے.یہ حالت
ایمان کی صورت میں ہوتی ہے.دوسری قسم عملی رنگ رکھتی ہے جیسا کہ يُقِيمُونَ الصَّلوةَ میں
فرمایا ہے.انسان کی وہ نمازیں جو شبہات اور وساوس میں مبتلا ہیں کھڑی نہیں ہوتی ہیں.اللہ
تعالیٰ نے يَقْرَءُون نہیں فرمایا بلکہ يُقِيمُونَ فرمایا یعنی جو حق ہے اس کے ادا کرنے کا.سنو!
ہر ایک چیز کی ایک علت غائی ہوتی ہے اگر اس سے رہ جاوے تو وہ بے فائدہ ہو جاتی ہے مثلاً
ایک بیل جو قلبہ رانی کے واسطے خریدا گیا ہے اپنے منصب پر اس وقت قائم سمجھا جاوے گا کہ وہ
کر کے دکھا دے نہ صرف یہ کہ اس کی غرض وغایت کھانے پینے ہی تک محدودر ہے.وہ اپنی
علت غائی سے دور ہے اور اس قابل ہے کہ اس کو ذبح کیا جاوے.اسی طرح يُقِيمُونَ
الصَّلوة سے لوازم الصلوۃ معراج ہے اور یہ وہ حالت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق شروع
ہوتا ہے.مکاشفات اور رویا صالحہ آتے ہیں ، لوگوں سے انقطاع ہوتا جاتا ہے اور خدا کی
طرف ایک تعلق پیدا ہونے لگتا ہے یہاں تک کہ تبتل تام ہو کر خدا میں جاملتا ہے.اصلی جلنے کو کہتے ہیں جیسے کباب کو بھونا جاتا ہے اسی طرح نماز میں سوزش لازمی ہے.جب تک دل بریان نہ ہو نماز میں لذت اور سرور پیدا نہیں ہوتا اور اصل تو یہ ہے کہ نماز ہی اپنے
سچے معنوں میں اُس وقت ہوتی ہے نماز میں یہ شرط ہے کہ وہ بجمیع شرائط ادا ہو جب تک وہ
ادا نہ ہو وہ نماز نہیں ہے اور نہ وہ کیفیت جو صلو میں میل نما کی ہے حاصل ہوتی ہے.یادرکھو صلوۃ میں حال اور قال دونوں کا جمع ہونا ضروری ہے.بعض وقت اعلام تصویری ہوتا
185
Page 194
ہے ایسی تصویر دکھائی جاتی ہے جس سے دیکھنے والے کو پتہ ملتا ہے کہ اس کا منشاء یہ ہے.ایسا
ہی صلوۃ میں منشاء الہی کی تصویر ہے.نماز میں جیسے زبان سے کچھ پڑھا جاتا ہے ویسے ہی اعضا
اور جوارح کی حرکات سے کچھ دکھایا بھی جاتا ہے جب انسان کھڑا ہوتا ہے اور تحمید و تسبیح کرتا
ا
ہے اُس کا نام قیام رکھا ہے اب ہر ایک شخص جانتا ہے کہ حمدوثنا کے مناسب حال قیام ہی
ہے.بادشاہوں کے سامنے جب قصائد سنائے جاتے ہیں تو آخر کھڑے ہو کر ہی پیش کرتے
ہیں.ادھر تو ظاہری طور پر قیام رکھا ہی ہے اور زبان سے حمد و ثنا بھی رکھی ہے.مطلب اس کا یہی
ہے کہ روحانی طور پر بھی اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑا ہو.حمد ایک بات پر قائم ہو کر کی جاتی ہے جو
شخص مصدق ہو کر کسی کی تعریف کرتا ہے تو وہ ایک رائے پر قائم ہو جاتا ہے اس الحمد للہ کہنے
والے کے واسطے یہ ضروری ہوا کہ وہ بچے طور پر الحمد للہ اسی وقت کہہ سکتا ہے کہ پورے طور
پر اس کو یقین ہو جائے کہ جمیع اقسام محامد کے اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہیں.جب یہ بات دل میں
انشراح کے ساتھ پیدا ہوگئی تو یہ روحانی قیام ہے کیونکہ دل اس پر قائم ہو جاتا ہے.اور وہ سمجھا
جاتا ہے کہ کھڑا ہے.حال کے موافق کھڑا ہو گیا تا کہ روحانی قیام نصیب ہو.پھر رکوع میں سُبحان ربی العظیم کہتا ہے.قاعدہ کی بات ہے کہ جب کسی کی عظمت
مان لیتے ہیں تو اس کے حضور جھکتے ہیں عظمت کا تقاضا ہے کہ اس کے لئے رکوع کرے.پس
سُبحان ربي العظيم زبان سے کہا اور حال سے جھکنا دکھایا.یہ اس قول کے ساتھ حال دکھایا.پھر تیسرا قول ہے سُبْحَانَ رَبِّي الأعلى، اَفْعَلُ التَّفضِیل ہے.یہ بالذات سجدہ کو چاہتا
ہے.اس لئے اس کے ساتھ حالی تصویر سجدہ میں گرے گا.اور اس اقرار کے مناسب حال
ہیئت فی الفور اختیار کرلی.اس قال کے ساتھ تین حال جسمانی ہیں ایک تصویر اس کے آگے پیش کی ہے ہر ایک قسم کا
قیام بھی کرتا ہے زبان جو جسم کا ٹکڑا ہے اس نے بھی کہا اور وہ شامل ہوگئی.تیسری چیز اور ہے وہ اگر شامل نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی وہ کیا ہے؟ وہ قلب ہے.اس کے
186
Page 195
لئے ضروری ہے کہ قلب کا قیام ہو اور اللہ تعالیٰ اس پر نظر کر کے دیکھے کہ در حقیقت وہ حمد بھی کرتا
ہے اور کھڑ ابھی ہے.اور روح بھی کھڑا ہوا حمد کرتا ہے.جسم ہی نہیں بلکہ روح بھی کھڑا ہے اور
جب سُبحان ربی العظیم کہتا ہے تو دیکھے کہ اتنا ہی نہیں کہ صرف عظمت کا اقرار ہی کیا ہے.نہیں بلکہ ساتھ ہی جھکا بھی ہے اور اس کے ساتھ ہی روح بھی جھک گیا ہے.پھر تیسری نظر
میں خدا کے حضور سجدہ میں گرا ہے اس کی علو شان کو ملاحظہ میں لاکر اس کے ساتھ ہی دیکھے کہ
روح بھی الوہیت کے آستانہ پر گرا ہوا ہے.غرض یہ حالت جب تک پیدا نہ ہولے اس وقت
تک مطمئن نہ ہو کیونکہ یقیمُونَ الصَّلوة کے یہی معنی ہیں.اگر یہ سوال ہو کہ یہ حالت پیدا کیوں کر ہو؟ تو اس کا جواب اتنا ہی ہے کہ نماز پر مداومت کی
جاوے اور وساوس اور شبہات سے پریشان نہ ہو.ابتدائی حالت میں شکوک وشبہات سے ایک
جنگ ضرور ہوتی ہے.اس کا علاج یہی ہے کہ نہ تھکنے والے استقلال اور صبر کے ساتھ لگا ر ہے
اور خدا تعالیٰ سے دُعائیں مانگتا ر ہے.آخر وہ حالت پیدا ہو جاتی ہے جس کا میں نے ابھی ذکر
کیا ہے.یہ تقوی عملی کا ایک جزو ہے.اور دوسری جزو اس ( تقویٰ) کی حما رَزَقُهُمْ يُنْفِقُونَ ہے.جو کچھ دے رکھا ہے اس
میں سے خرچ کرتے ہیں.عام لوگ رزق سے مراد اشیاء خوردنی لیتے ہیں یہ غلط ہے.جو کچھ
قوی کو دیا جاوے وہ بھی رزق ہے.علوم وفنون وغیرہ معارف حقائق عطا ہوتے ہیں یا جسمانی
طور پر معاش مال میں فراخی ہو.رزق میں حکومت بھی شامل ہے اور اخلاق فاضلہ بھی رزق ہی
میں داخل ہیں.یہاں
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے
ہیں یعنی روٹی میں سے روٹی دیتے ہیں، علم میں سے علم اور اخلاق میں سے اخلاق.لیکن اگر کوئی یہاں یہ اعتراض کرے کہ مِمَّا رَزَقْنُهُمْ يُنْفِقُونَ کیوں فرمایا ؟ ہما کے
لفظ سے مکمل کی بو آتی ہے.چاہئے تھا کہ.ہر چہ داری خرچ کن در راه او
اصل بات یہ ہے کہ اس سے بخل ثابت نہیں ہوتا.قرآن شریف خدائے حکیم کا کلام
187
Page 196
ہے.حکمت کے معنے ہیں شے بر محل داشتن.پس مِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنْفِقُونَ میں اسی امر کی
طرف اشارہ کیا ہے کہ محل اور موقع کو دیکھ کر خرچ کرو.جہاں تھوڑا خرچ کرنے کی ضرورت
ہے وہاں تھوڑ اخرچ کرو اور جہاں بہت خرچ کرنے کی ضرورت ہے وہاں بہت خرچ کرو.الحکم جلد 5 مؤرخہ 10 اپریل 1901ء صفحہ 2 تا 4)
ایک مرتبہ میں نے خیال کیا کہ صلوۃ میں اور دُعا میں کیا فرق ہے.حدیث شریف
میں آیا ہے الصَّلوةُ هِيَ الدُّعَاءُ الصَّلوةُ مُخُ الْعِبَادَةِ یعنی نماز ہی دُعا ہے، نما ز عبادت کا مغز
ہے.جب انسان کی دُعا محض دنیوی امور کے لئے ہو تو اس
کا نام صلوہ نہیں.لیکن جب انسان خدا
کو ملنا چاہتا ہے اور اُس کی رضا کو مد نظر رکھتا ہے اور ادب، انکسار، تواضع اور نہایت محویت کے
ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور میں کھڑا ہو کر اس کی رضا کا طالب ہوتا ہے تب وہ صلوۃ میں ہوتا ہے.اصل حقیقت دُعا کی وہ ہے جس کے ذریعہ سے خدا اور انسان کے درمیان رابطہ تعلق
بڑھے.یہی دُعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہوتی ہے اور انسان کو نامعقول
باتوں سے ہٹاتی ہے.اصل بات یہی ہے کہ انسان رضائے الہی کو حاصل کرے.اس کے
بعد روا ہے کہ انسان اپنی دنیوی ضروریات کے واسطے بھی دُعا کرے.یہ اس واسطے روا رکھا
گیا ہے کہ دنیوی مشکلات بعض دفعہ دینی معاملات میں بارج ہو جاتے ہیں.خاص کر خامی اور
پچ پنے کے زمانہ میں یہ امور ٹھو کر کا موجب بن جاتے ہیں.صلوۃ کا لفظ پُر سوز معنے پر دلالت
کرتا ہے جیسے آگ سے سوزش پیدا ہوتی ہے.ویسی ہی گدازش دُعا میں پیدا ہونی چاہیئے.جب ایسی حالت کو پہنچ جائے جیسے موت کی حالت ہوتی ہے تب اُس کا نام صلوۃ ہوتا ہے.( بدر جلد 1 نمبر 8 مؤرخہ 25 رمئی 1905 ، صفحہ 4)
صلوۃ کا لفظ اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ تیرے الفاظ اور دُعا ہی کافی نہیں بلکہ اس کے
ساتھ ضروری ہے کہ ایک سوزش رقت اور درد ساتھ ہو.خدا تعالیٰ کسی دُعا کو نہیں سنتا جب تک
دُعا کرنے والا موت تک نہ پہنچ جاوے.دُعا مانگنا ایک مشکل امر ہے اور لوگ اس کی حقیقت
سے محض ناواقف ہیں بہت سے لوگ مجھے خط لکھتے ہیں کہ ہم نے فلاں وقت فلاں امر کے لئے
188
Page 197
دعا کی تھی مگر اُس کا اثر نہ ہوا.اور اس طرح پر وہ خدا تعالیٰ سے بدظنی کرتے ہیں اور مایوس ہو کر
بلاک ہو جاتے ہیں وہ نہیں جانتے کہ جب تک دُعا کے لوازم ساتھ نہ ہوں وہ دُعا کوئی فائدہ
نہیں پہنچاسکتی.دُعا کےلوازم میں سے یہ ہے کہ دل پگھل جاوے اور روح پانی کی طرح
حضرت احدیت کے آستانہ پر گرے اور ایک کرب اور اضطراب اس میں پیدا ہو اور ساتھ ہی
انسان بے صبر اور جلد باز نہ ہو بلکہ صبر اور استقامت کے ساتھ دُعا میں لگا رہے پھر توقع کی
جاتی ہے کہ وہ دُعا قبول ہوگی.( بدر جلد 6 نمبر 1-2 مؤرخہ 10 جنوری 1907 صفحہ 12)
نماز اس وقت حقیقی نماز کہلاتی ہے جبکہ اللہ تعالیٰ سے سچا اور پاک تعلق ہو اور اللہ تعالیٰ
کی رضا اور اطاعت میں اس حد تک فنا ہو اور یہاں تک دین کو دنیا پر مقدم کرلے کہ خدا تعالیٰ
کی راہ میں جان تک دے دینے اور مرنے کے لئے تیار ہو جائے جب یہ حالت انسان میں پیدا
ہو جائے اس وقت کہا جائے گا کہ اس کی نما زنماز ہے مگر جب تک یہ حقیقت انسان کے اندر
پیدا نہیں ہوتی اور سچا اخلاص اور وفاداری کا نمونہ نہیں دکھا تا اُس وقت تک اس کی نمازیں اور
دوسرے اعمال بے اثر ہیں.الحکم جلد 8 نمبر 1 مورخہ 10 /جنوری 1904 ، صفحہ 3)
جب تک انسان کامل طور پر توحید پر کار بند نہیں ہوتا.اس میں اسلام کی محبت اور عظمت
قائم نہیں ہوتی....نماز کی لذت اور سرور اسے حاصل نہیں ہوسکتا.مدار اسی بات پر ہے کہ جب
تک بڑے ارادے ناپاک اور گندے منصوبے بھسم نہ ہوں انانیت اور شیخی دور ہو کر نیستی اور
فروتنی نہ آئے خدا کا سچا بندہ نہیں کہلا سکتا اور عبودیت کاملہ کے سکھانے کے لئے بہترین معلم
اور افضل ترین ذریعہ نماز ہی ہے.میں پھر
تمہیں بتلاتا ہوں کہ اگر خدا تعالیٰ سے سچا تعلق حقیقی ارتباط قائم کرنا چاہتے ہو تو نماز
پر کاربند ہو جاؤ اور ایسے کاربند بنو کہ تمہارا جسم نہ تمہاری زبان بلکہ تمہاری روح کے ارادے
اور جذ بے سب کے سب ہمہ تن نماز ہو جائیں.الحکم جلد 3 نمبر 13 مورخہ 12 /اپریل 1899 ، صفحہ 7)
189
Page 198
* میرا تو یہ مذہب ہے کہ اگر دس دن بھی نماز کوسنوار کر پڑھیں تو تنویر قلب ہو
جاتی ہے مگر یہاں تو پچاس پچاس برس تک نماز پڑھنے والے دیکھے گئے ہیں کہ بدستور و بدنیا
اور سفلی زندگی میں نگونسار ہیں اور انہیں نہیں معلوم کہ وہ نمازوں میں کیا پڑھتے ہیں اور استغفار کیا
چیز ہے؟...یاد رکھو رسم اور چیز ہے اور صلوٰۃ اور چیز.صلوۃ ایسی چیز ہے کہ اس سے بڑھ کر
اللہ تعالیٰ کے قرب کا کوئی قریب ذریعہ نہیں.یہ قرب کی کنجی ہے.اسی سے کشوف ہوتے
ہیں.اسی سے الہامات اور مکالمات ہوتے ہیں.یہ دُعاؤں کے قبول ہونے کا ایک ذریعہ
ہے لیکن اگر کوئی اس کو اچھی طرح سے سمجھ کر ادا نہیں کرتا تو وہ رسم اور عادت کا پابند ہے.نماز میں جو جماعت کا زیادہ ثواب رکھا ہے اس میں یہی غرض ہے کہ وحدت پیدا ہوتی ہے اور
پھر اس وحدت
کو عملی رنگ میں لانے کی یہاں تک ہدایت اور تاکید ہے کہ باہم پاؤں بھی مساوی
ہوں اور صف سیدھی ہو اور ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوں.اس سے مطلب یہ ہے کہ گویا ایک
ہی انسان کا حکم رکھیں اور ایک کے انوار دوسرے میں سرایت کرسکیں.وہ تمیز جس سے خودی اور
خود غرضی پیدا ہوتی ہے نہ رہے.یہ خوب یا درکھو کہ انسان میں یہ قوت ہے کہ وہ دوسرے کے انوار کو
جذب کرتا ہے.پھر اسی وحدت کے لئے حکم ہے کہ روزانہ نماز میں محلہ کی مسجد میں اور ہفتہ کے بعد
شہر کی مسجد میں اور پھر سال کے بعد عید گاہ میں جمع ہوں اور گل زمین کے مسلمان سال میں ایک مرتبہ
سبیت اللہ میں اکٹھے ہوں.ان تمام احکام کی غرض وہی وحدت ہے.لیکچر لدھیانہ، روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 281 282)
متقی کا لفظ باب افتعال سے آتا ہے اور یہ باب تصنع کے لئے آتا ہے.اس سے
معلوم ہوا کہ متقی کو بڑا مجاہدہ اور کوشش کرنی پڑتی ہے اور اس حالت میں وہ نفس لوامہ کے
نیچے ہوتا ہے اور جب حیوانی زندگی بسر کرتا ہے اُس وقت اٹارہ کے نیچے ہوتا ہے اور مجاہدہ کی
حالت سے نکل کر جب غالب آجاتا ہے تو مطمئنہ کی حالت میں ہوتا ہے.متقی نفس امارہ کی
حالت سے نکل کر آتا ہے اور تو امہ کے نیچے ہوتا ہے اسی لئے منتقی کی شان میں آیا ہے کہ وہ نماز
کو کھڑی کرتے ہیں گویا اس میں بھی ایک قسم کی لڑائی ہی کی حالت ہوتی ہے وساوس اور اوہام
190
Page 199
آ کر حیران کرتے ہیں مگر وہ گھبراتا نہیں اور یہ وساوس اُس کو درماندہ نہیں کر سکتے.وہ بار بار خدا
تعالیٰ کی استعانت چاہتا ہے اور خدا کے حضور چلاتا اور روتا ہے یہاں تک کہ غالب آ جاتا ہے
ایسا ہی مال کے خرچ کرنے میں بھی شیطان اس کو روکتا ہے اور اسراف اور انفاق فی سبیل اللہ
کو یکساں دکھاتا ہے حالانکہ ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے.اسراف کرنے والا اپنے
مال کو ضائع کرتا ہے مگر فی سبیل اللہ خرچ کرنے والا اس کو پھر پاتا ہے اور خرچ سے زیادہ پاتا
ہے اس لئے ہی مِمَّا رَزَقُهُمْ يُنْفِقُونَ فرمایا ہے.الحکم جلد 5 نمبر 30 مورخہ 17 /اگست 1901، صفحہ 2)
دولت مند اور متمول لوگ دین کی خدمت اچھی طرح کر سکتے ہیں اسی لئے خدا تعالیٰ
نے ممَّا رَزَقُهُم يُنفِقُونَ متقیوں کی صفت کا ایک جز وقرار دیا ہے.یہاں مال کی کوئی
خصوصیت نہیں ہے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے کسی کو دیا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے.مقصود
اس سے یہ ہے کہ انسان اپنے بنی نوع کا ہمدرد اور معاون بنے.اللہ تعالیٰ کی شریعت کا انحصار دو
ہی باتوں پر ہے.تعظیم لامر اللہ اور شفقت علی خلق الله - پس مِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنْفِقُونَ میں
شفقت علی خلق اللہ کی تعلیم ہے.وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ
هُمْ يُوقِنُونَ
یعنی متقی وہ ہوتے ہیں جو پہلے نازل شدہ کتب پر اور تجھ پر جو کتاب نازل ہوئی اس پر
( ایمان لاتے ) اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں.یہ امر بھی تکلف سے خالی نہیں.ابھی تک
ایمان ایک محجوبیت کے رنگ میں ہے.متقی کی آنکھیں معرفت اور بصیرت کی نہیں.اُس
نے تقویٰ سے شیطان کا مقابلہ کر کے ابھی ایک بات کو مان لیا ہے.یہی حال اس وقت
ہماری جماعت کا ہے.انہوں نے بھی تقویٰ سے مانا تو ہے اور ابھی وہ نہیں جانتے کہ یہ
جماعت کہاں تک نشو ونما الہی ہاتھوں سے پانے والی ہے.سو یہ ایک ایمان ہے جو بالآخر
فائدہ رساں ہوگا.191
Page 200
یقین کا لفظ عام طور پر جب استعمال ہو تو اس سے مراد اس کا ادنی درجہ ہوتا ہے.یعنی علم
کے تین مدارج میں سے ادنی درجہ کا علم یعنی علم الیقین اس درجہ پر اتقا والا ہوتا ہے.مگر بعد
اس کے عین الیقین اور حق الیقین کا مرتبہ بھی تقویٰ کے مراحل طے کرنے کے بعد حاصل کر لیتا
ہے.تقویٰ کوئی چھوٹی چیز نہیں.اس کے ذریعہ ان تمام شیطانوں کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے جو
انسان کی ہر ایک اندرونی طاقت وقوت پر غلبہ پائی ہوئی ہیں.یہ تمام قوتیں نفس اٹارہ کی
حالت میں انسان کے اندر شیطان ہیں.اگر اصلاح نہ پائیں گے تو انسان کو غلام کرلیں گے.علم و عقل ہی بُرے طور پر استعمال ہو کر شیطان ہو جاتے ہیں.متقی کا کام ان کی اور ایسا ہی اور
گل قومی کی تعدیل کرنا ہے.ایسا ہی جو لوگ انتقام، غضب یا نکاح کو ہر حال میں بُرا جانتے
ہیں.وہ بھی صحیفہ قدرت کے مخالف ہیں اور قومی انسانی کا مقابلہ کرتے ہیں.سچا مذہب وہی
ہے جو انسانی قویٰ کا مرتی ہو، نہ کہ اُن کا استیصال کرے.رجولیت یا غضب جو خدا تعالیٰ کی
طرف سے فطرت انسانی میں رکھے گئے ہیں اُن کو چھوڑنا خدا کا مقابلہ کرنا ہے.جیسے
تارک الدنیا ہونا یا راہب بن جانا یہ تمام حق العباد کو تلف کرنے والے ہیں.اگر یہ امر ایسا ہی
ہوتا تو گویا اُس خدا پر اعتراض ہے جس نے یہ قومی ہم میں پیدا کئے.رپورٹ جلسہ سالانہ 1897 صفحہ 48،47)
طالب نجات وہ ہے جو خاتم النبیین پیغمبر آخر الز مان پر جو کچھ اتارا گیا ہے اس پر
ایمان لاوے اور اس پیغمبر سے پہلے جو کتابیں اور صحیفے سابقہ انبیاء اور رسولوں پر نازل ہوئے اُن
کو بھی مانے.وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ اور طالب نجات وہ ہے جو پچھلی آنے والی گھڑی یعنی
قیامت پر یقین رکھے اور جزاوسز امانتا ہو.( الحکم جلد 8 نمبر 35 - 34 صفحہ 9_10 تا 17 اکتوبر 1904ء)
میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ قرآن شریف کی وحی اور اس سے پہلی وحی پر ایمان
لانے کا ذکر تو قرآن شریف میں موجود ہے.ہماری وحی پر ایمان لانے کا ذکر کیوں نہیں.اسی امر
پر توجہ کر رہا تھا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے بطور القاء کے یکا یک میرے دل میں یہ بات ڈالی گئی
192
Page 201
که آید كريمه وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ
يُوقِنُون میں تینوں وحیوں کا ذکر ہے.مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ سے قرآن شریف کی وحی اور مَا اُنْزِلَ مِن قَبْلِكَ سے انبیاء سابقین کی وحی
اور آخرۃ سے مراد مسیح موعود کی وحی ہے.آخرة کے معنے ہیں پیچھے آنے والی.وہ پیچھے آنے
والی چیز کیا ہے؟ سیاق کلام سے ظاہر ہے کہ یہاں پیچھے آنے والی چیز سے مراد وہ وحی ہے جو
قرآن کریم کے بعد نازل ہوگی کیونکہ اس سے پہلے وحیوں کا ذکر ہے.ایک وہ جو آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ، دوسری وہ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل نازل ہوئی اور
تیسری وہ جو آپ کے بعد آنے والی تھی.ریویو آف ریلیجز، جلد 14 نمبر 4 بابت ماہ مارچ واپریل 1905 ، صفحہ 164 حاشیہ)
أولَئِكَ عَلى هُدى مَنْ تَعِيمُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
یعنی جن لوگوں میں مذکورہ بالا اوصاف موجود ہوں وہ لوگ اپنے پروردگار کی سیدھی راہ پر
ہیں اور وہی لوگ نجات یابندہ اور فرقہ ناجیہ کے لوگ ہیں.یہی طریق نجات ہے جو اسلام نے
پیش کیا ہے.یہ راستہ کیا صاف اور سیدھا ہے.طالب نجات کو لازم ہے کہ وہ اپنی عقل کو
الہام و وحی الہی کے ماتحت چلائے ورنہ بھٹک جائے گا.الحکم جلد 8 نمبر 34 ، 35 مورخہ 10 تا 17 اکتوبر 1904 ، صفحہ 9)
إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ وَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرُهُمْ لَا
يُؤْمِنُونَ.....حمد اس جگہ خدائے تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ جولوگ خدائے تعالیٰ کے علم میں ہدایت
پانے کے لائق ہیں اور اپنی اصل فطرت میں صفت تقویٰ سے متصف ہیں وہ ضرور ہدایت
پا جائیں گے.اور پھر ان آیات میں جو اس آیت کے بعد میں لکھی گئی ہیں اسی کی زیادہ تر تفصیل
کردی اور فرمایا کہ جس قدر لوگ ( خدا کے علم میں ) ایمان لانے والے ہیں وہ اگر چہ ہنوز
مسلمانوں میں شامل نہیں ہوئے پر آہستہ آہستہ سب شامل ہو جائیں گے اور وہی لوگ باہر رہ
جائیں گے جن کو خدا خوب جانتا ہے کہ طریقہ ء حقہ اسلام قبول نہیں کریں گے اور گو ان کو
193
Page 202
نصیحت کی جائے یا نہ کی جائے ایمان نہیں لائیں گے یا مراتب کاملہ تقویٰ و معرفت تک نہیں
پہنچیں گے.غرض ان آیات میں خدائے تعالیٰ نے کھول کر بتلا دیا کہ ہدایت قرآنی سے صرف متقی
منتفع ہو سکتے ہیں جن کی اصل فطرت میں غلبہ کسی ظلمت نفسانی کا نہیں اور یہ ہدایت ان تک
ضرور پہنچ رہے گی.لیکن جو لوگ متقی نہیں ہیں نہ وہ ہدایت قرآنی سے کچھ نفع اٹھاتے ہیں اور نہ
یہ ضرور ہے کہ خواہ مخواہ ان تک ہدایت پہنچ جائے.خلاصہ جواب یہ ہے کہ دنیا میں دوطور کے
آدمی پائے جاتے ہیں.بعض متقی اور طالب حق جو ہدایت کو قبول کر لیتے ہیں اور بعض
مفسد الطبع جن کو نصیحت کرنا نہ کرنا برابر ہوتا ہے.( براہین احمدیہ چہار حصص، روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 201 تا202)
خَتَمَ اللهُ عَلى قُلُوبِهِمْ وَ عَلى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَ
لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ
خدا تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا بلکہ انسان اپنے نفس پر آپ ظلم کرتا ہے.عادۃ اللہ یہ ہے کہ
جب ایک فعل یا عمل انسان سے صادر ہوتا ہے تو جو کچھ اس میں اثر مخفی یا کوئی خاصیت چھپی ہوئی
ہوتی ہے خدا تعالیٰ ضرور اس کو ظاہر کر دیتا ہے.مثلاً جس وقت ہم کسی کوٹھڑی کے چاروں
طرف سے دروازے بند کر دیں گے تو یہ ہمارا ایک فعل ہے جو ہم نے کیا اور خدا تعالیٰ کی طرف
سے اس پر اثر یہ مترتب ہوگا کہ ہماری کوٹھڑی میں اندھیرا ہو جائے گا اور اندھیرا کرنا خدا کا فعل
ہے جو قدیم سے اس کے قانونِ قدرت میں مندرج ہے.ایسا ہی جب ہم ایک وزن
کافی تک زہر
کھالیں گے تو کچھ شک نہیں کہ یہ ہمارا فعل ہوگا.پھر بعد اس کے ہمیں ماردینا یہ خدا کا فعل ہے
جو قدیم سے اس کے قانونِ قدرت میں مندرج ہے.غرض ہمارے فعل کے ساتھ ایک فعل خدا کا
ضرور ہوتا ہے جو ہمارے فعل کے بعد ظہور میں آتا اور اُس کا نتیجہ لازمی ہوتا ہے.سو یہ انتظام جیسا
کہ ظاہر سے متعلق ہے ایسا ہی باطن سے بھی متعلق ہے.ہر ایک ہمارا نیک یا بد کام ضرور اپنے
ساتھ ایک اثر رکھتا ہے جو ہمارے فعل کے بعد ظہور میں آتا ہے.194
Page 203
اور قرآن شریف میں جو خَتَمَ اللهُ عَلى قُلُوبهم آیا ہے اس میں خدا کے مہر لگانے کے یہی
معنی ہیں کہ جب انسان بدی کرتا ہے تو بدی کا نتیجہ اثر کے طور پر اس کے دل پر اور منہ پر
خدا تعالیٰ ظاہر کر دیتا ہے اور یہی معنے اس آیت کے ہیں کہ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ
قُلُوبَهُمُ (الصف (6) یعنی جب کہ وہ حق سے پھر گئے تو خدا تعالیٰ نے ان کے دل کو حق کی
مناسبت سے دور ڈال دیا اور آخر کو معاندانہ جوش کے اثروں سے ایک عجیب کا یا پلٹ ان میں
ظہور میں آئی اور ایسے بگڑے کہ گویا وہ وہ نہ رہے اور رفتہ رفتہ نفسانی مخالفت کے زہر نے ان
کے انوار فطرت کو دبا لیا.کتاب البریہ روحانی خزائن جلد 13 صفحہ 48،47)
* آریہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن شریف میں لکھا ہے خَتَمَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِم
کہ خدا نے دلوں پر مہر کر دی ہے تو اس میں انسان کا کیا قصور ہے؟ یہ ان لوگوں کی کو نہ اندیشی
ہے کہ ایک کلام کے ماقبل اور مابعد پر نظر نہیں ڈالتے ورنہ قرآن شریف نے صاف طور پر
بتلایا ہے کہ یہ مہر جو خدا کی طرف سے لگتی ہے یہ دراصل انسانی افعال کا نتیجہ ہے.کیونکہ جب
ایک فعل انسان کی طرف سے صادر ہوتا ہے تو سنت اللہ یہی ہے کہ ایک فعل خدا کی طرف سے
بھی صادر ہو.جیسے ایک شخص جب اپنے مکان کے دروازے بند کر دے تو یہ اس کا فعل ہے
اور اس پر خدا کا فعل یہ صادر ہو گا کہ اس مکان میں اندھیرا کر دے کیونکہ روشنی اندر آنے کے جو
ذریعے تھے وہ اُس نے خود اپنے لئے بند کر دئیے.اسی طرح اس مہر کے اسباب کا ذکر خدا تعالیٰ
نے قرآن شریف میں دوسری جگہ کیا ہے جہاں لکھا ہے: فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللهُ
(الصف 6) کہ جب انہوں نے کجی اختیار کی تو خدا نے ان کو بج کر دیا.اسی کا نام مہر ہے لیکن
ہمارا خدا ایسا نہیں کہ پھر اس مہر کو دور نہ کر سکے.چنانچہ اُس نے مہر لگنے کے اسباب بیان کئے
ہیں تو ساتھ ہی وہ اسباب بھی بتلا دیئے ہیں جن سے یہ مہر اٹھ جاتی ہے.جیسے کہ یہ فرمایا ہے
إِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا (بنی اسرائیل (26).( البدر، جلد 2 نمبر 34 مورخہ 11 ستمبر 1903 ، صفحہ 367)
195
Page 204
فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا
كَانُوا يَكْذِبُونَ
جب تک ایک مرض کے مواد مخفی ہیں تب تک اس مرض کا کچھ علاج نہیں ہوسکتالیکن
مواد کے ظہور اور بروز کے وقت ہر یک طور کی تدبیر ہوسکتی ہے.انبیاء نے جو سخت الفاظ
استعمال کئے حقیقت میں ان کا مطلب تحریک ہی تھا تا خلق اللہ میں ایک جوش پیدا ہو جائے
اور خواب غفلت سے اس ٹھو کر کے ساتھ بیدار ہو جائیں اور دین کی طرف خوض اور فکر کی نگاہیں
دوڑانا شروع کر دیں اور اس راہ میں حرکت کریں گو وہ مخالفانہ حرکت ہی سہی اور اپنے دلوں کا
اہل حق کے دلوں کے ساتھ ایک تعلق پیدا کرلیں گو وہ عدوانہ تعلق ہی کیوں نہ ہو.اسی کی طرف
اللہ جل شانه اشارہ فرماتا ہے فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا یقینا سمجھنا چاہئے کہ
دین اسلام کو سچے دل سے ایک دن وہی لوگ قبول کریں گے جو بباعث سخت اور پرزور
جگانے والی تحریکوں کے کتب دینیہ کی ورق گردانی میں لگ گئے ہیں اور جوش کے ساتھ اس راہ
کی طرف قدم اٹھا ر ہے ہیں گو وہ قدم مخالفانہ ہی سہی.(ازالہ اوہام، روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 118)
جب کوئی ابتلا اور آزمائش آتی ہے تو وہ انسان کو ننگا کر کے دکھا دیتی ہے.اُس وقت
وہ مرض جو دل میں ہوتی ہے اپنا پورا اثر کر کے انسان کو بلاک کر دیتی ہے.فِي قُلُوبِهِم
مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللهُ مَرَضًا.یہ مرض ابتلا ہی کے وقت بڑھتی اور اپنا پورا زور دکھاتی ہے.خدا
تعالی کی یہ بھی عادت ہے کہ وہ دلوں کی مخفی قوتوں کو ظاہر کر دیتا ہے.جو شخص اپنے دل میں
ایک نور رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا صدق اور اخلاص ظاہر کر دیتا ہے اور جو دل میں محبت اور
شرارت رکھتا ہے اس کو بھی کھول کر دکھا دیتا ہے اور کوئی بات چھپی ہوئی نہیں رہ سکتی.احکم جلد 10 نمبر 1.10 جنوری 1906 صفحہ 5)
نرا بدیوں سے بچنا کوئی کمال نہیں.ہماری جماعت کو چاہئے کہ اسی پر بس نہ کرے.نہیں بلکہ انہیں دونو کمال حاصل کرنے کی سعی کرنی چاہئے جس کے لئے مجاہدہ اور دُعا سے کام
196
Page 205
لیں یعنی بدیوں سے بچیں اور نیکیاں کریں.ہماری جماعت کو چاہئے کہ وہ خدا کو سادہ نہ سمجھ لے
کہ وہ مکر و فریب میں آجائے گا.جو شخص سفلہ طبع ہو کر خدا تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہتا ہے اور نیکی
اور راست بازی کی چادر کے نیچے فریب کرتا ہے وہ یادر کھے کہ خدا تعالیٰ اسے اور بھی رسوا
کرے گا.فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللهُ مَرَضًا.ایسے ہی لوگوں کے لئے فرمایا ہے.نفاق اور ریا کاری کی زندگی لعنتی زندگی ہے یہ چھپ نہیں سکتی.آخر ظاہر ہو کر رہتی ہے اور
پھر سخت ذلیل کرتی ہے.خدا تعالیٰ کسی چیز کو چھپاتا نہیں نہ نیکی کو نہ ہدی کو.سچ نکوکار اپنی
نیکیوں کو چھپاتے ہیں مگر خدا تعالیٰ انہیں ظاہر کر دیتا ہے.حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب حکم
ہوا کہ تو پیغمبر ہو کر فرعون کے پاس جا تو انہوں نے عذر ہی کیا.اس میں سر یہ تھا کہ جولوگ خدا
کے لئے پورا اخلاص رکھتے ہیں وہ نمود اور ریا سے بالکل پاک ہوتے ہیں.سچے اخلاص کی یہی
نشانی ہے کہ کبھی خیال نہ آوے کہ دنیا ہمیں کیا کہتی ہے.جو شخص اپنے دل میں اس امر کا ذرا
بھی شائبہ رکھتا ہے وہ بھی شرک کرتا ہے.الحکم جلد 10 نمبر 25 مورخہ 17 جولائی 1906 ، صفحہ 3)
وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا
إنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُرُونَ.اور جب ان کو کہا جائے کہ تم زمین میں فساد مت کرو اور کفر اور شرک اور بد عقیدگی کومت
پھیلاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ہی راستہ ٹھیک ہے اور ہم مفسد نہیں ہیں بلکہ مصلح اور ریفارمر ہیں.خبر دار ہو! یہی لوگ مفسد ہیں جو زمین پر فساد کر رہے ہیں.( براہین احمدیہ چہار حصص ، روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 604 اشیه در حاشیہ نمبر 3)
وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ امِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا أَمَنَ
السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ
اور جب اُن کو کہا جائے کہ ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے ہیں.تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم
ایسا ہی ایمان لاویں جیسے بے وقوف ایمان لائے ہیں؟ خبر دار ہو! وہی بے وقوف ہیں مگر
197
Page 206
جانتے نہیں.براہین احمدیہ جہار حصص، روحانی خزائن جلد 1 صفحه 607 حاشیه در حاشیہ نمبر 3)
وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيْطِيْنِهِمْ قَالُوا
إِنَّا مَعَكُمْ إِثْمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ
یعنی جب وہ مسلمانوں کے پاس جاتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور جب
وہ دوسروں کے پاس جاتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور یہ وہ لوگ ہوتے
ہیں جن کو قرآن شریف میں منافق کہا گیا ہے اس لئے جب تک کوئی شخص پورے طور پر
قرآن مجید پر عمل نہیں کرتا تب تک وہ پورا پورا اسلام میں بھی داخل نہیں ہوتا.حکم جلد 12 نمبر 1.مورخہ 2 جنوری 1908ء)
ماخوذ از تفسیر حضرت مسیح موعود علیہ السلام )
حضرت
خلیفہ المسیح الاول رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں :
الم.اِس قسم کے الفاظ قرآن شریف کی اکثر سورتوں میں آتے ہیں اور ان کا نام
عربی زبان میں حروف مقطعات ہے اور دراصل یہ مختصر نویسی کا ایک طریق ہے.انگریزی
زبان میں بھی اس کی نظیریں موجود ہیں جیسے ایم.اے اور بی.اے اور ایم.ڈی وغیرہ.ہر
ایک محکمہ اور دفتر کی اصطلاح اختصار الگ الگ ہے.محدثین نے اس سے کام لیا ہے چنانچہ
بخاری کی بجائے لفظ خ لکھتے ہیں.طب میں بھی اس سے کام لیتے ہیں.بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ
الرّحیم کی جگہ بسملہ کہتے ہیں جس سے مقصود ساری آیت ہوتی ہے.اسی طرح لا حول
کے لئے حوقل.اسی طرح کا ایک الہام حضرت مسیح موعود کو ہوا تھا کہ تلاش جس کے معنے
ہیں يَا مَنْ لَا شَرِيكَ لَهُ.غرض ان مقطعات میں باریک اشارات ہوتے ہیں.ذلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ.یہ وہ لکھی ہوئی چیز ہے لکھی ہوئی اس لئے فرمایا کہ
جب آیت نازل ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اہتمام سے اپنے سامنے لکھالیتے.198
Page 207
دوسری وجہ یہ کہ کتيبة لشکر کوبھی کہتے ہیں اور جیسے لشکر بہت سے افراد کو اپنے اندر جمع رکھتا
ہے اسی طرح یہ کتاب بہت سے مضامین کو اپنے اندر لئے ہوئے ہے.اور جیسے لشکروں سے
دشمن بھاگتے ہیں ایسے ہی شبہات انسانیہ اس کتاب کے لشکر سے بھاگ جاتے ہیں.اس لئے
فرمايا لا ريب فيه - یعنی یہ ایک ایسی عظیم الشان کتاب ہے جس کے عظیم الشان ہونے میں
کچھ بھی شک نہیں یا جس میں کسی قسم کی کوئی شبہ والی بات نہیں.پھر ذلك الكتاب میں جو فرمایا یہی ایک کتاب ہے.تو اس سے ظاہر ہے کہ نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ نے کوئی اور کتاب نہیں دیکھی جس کو کتاب کہا جاسکے.وَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ
هُمْ يُوقِنُونَ
اور وہ لوگ جو اس (کلام الہی اور تمام اس وحی ) کے ساتھ ایمان لاتے ہیں جو تیری
طرف نازل ہو ا ( اور یہ امراُن پر واضح ہونے سے کہ خدا کی صفت تکلم ہمیشہ سے ہے ) تجھ
سے پہلے جو ( کلام الہی ) نازل ہوئی اس کو بھی مانتے ہیں اور اس صفت تکلم کو صرف تجھ
تک ہی محدود نہیں کرتے اور پیچھے آنے والی ( کلام الہی ) پر بھی یقین رکھتے ہیں.ان آیات میں اللہ تعالیٰ بتلاتا ہے کہ متقی کی صفت ایک یہ بھی ہے کہ مکالمہ الہی پر
اس کا ایمان ہوتا ہے اور وہ خدا کو کسی زمانہ ماضی، حال اور مستقبل میں گونگا نہیں مانتا.خدا تعالیٰ کے اس صفت تکلم کا ذکر ایمان، اقام الصلوۃ اور انفاق رزق کے بعد اس لئے
ضروری ہے کہ ان اعمال کا یہ تقاضا عملی طور پر ایک متقی کے واسطے ہونا چاہئے کہ آیا اس کی
محنت خداشناسی کا کوئی راستہ اس کے واسطے صاف کر رہی ہے کہ نہیں؟ اور جس راہ پر میں نے
قدم مارا ہے کیا اس پر دوسرے بھی قدم مار کر تستی یافتہ ہوئے ہیں کہ نہیں؟ تو اس کو یہ نظیر
زمانہ ماضی، حال میں میلتی ہے جس سے آئندہ کے لئے اُسے یقینی حالت پیدا ہو جاتی ہے.خدا تعالیٰ کی صفت تکلم کے بارے میں انسان کے تین گروہ ہیں.(1) وہ جو سرے سے
199
Page 208
انکار کرتے ہیں اور خدا کو گونگا مان بیٹھے ہیں (2) وہ جن کا یہ اعتقاد ہے کہ آزمنہ گزشتہ میں خدا
ایک حد تک بول چکا مگر آئندہ وہ لوگوں سے یا کسی سے بولتا نہیں (3) جن کا یہ اعتقاد ہے کہ
خدا تعالیٰ ہر زمانہ میں کلام کرتا ہے.تیسری قسم کے لوگ ہی ہمیشہ بامراد اور کامیاب ہوتے
رہے ہیں اور ہر ایک مومن کی یہی صفت ہونی چاہئے اور یہی اعتقاد ہے جو کہ اعلیٰ اعلیٰ مراتب
اور درجات حاصل کرواتا ہے.اس کے مخالف جس قدر عقیدے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو ایک کامل
ہستی نہیں مانتے بلکہ انکا اللہ ناقص خدا ہے.ان کا مذہب ناقص مذہب ہے.یہ شرف سچے
اور زندہ مذہب ہونے کا صرف اسلام ہی کو حاصل ہے اور چونکہ متکلم ازل سے ایک ہی ذاتِ
پاک ہے اس لئے یہ بھی ضروری ہے کہ اصولا ہر ایک زمانہ کے الہام کی تعلیم ایک ہی ہو اور ہر
زمانہ کے الہامات ایک دوسرے کے مؤید اور مصدق ہوں.مکالمہ الہی کے ذکر کا اس مقام پر یہ فائدہ بھی ہے کہ انسان کو حرص پیدا ہوتی رہے کہ خدا مجھ
سے بھی کلام کرے.اور اپنے اعمال کو سنوار کر ادا کرے.جیسے ایک شخص کو سخی دیکھ کر اس کے
پاس سوالی جمع ہو جاتے ہیں کہ ان کو بھی ملے اور جن اعمال سے یہ شرف مکالمہ کا حاصل ہوسکتا
ہے ان کو اول بیان فرما دیا ہے کہ وہ سب اعمال ما أُنْزِلَ اليك کے مطابق ہوں.مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ كو مَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ پر اس لئے مقدم رکھا ہے کہ سب سے مقدم
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اشباع ہے.یعنی وہ مَا اُنْزِل مِن قَبْلِكَ جس كو مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ تصديق
کرتا ہے.یہ نہیں کہ جو رطب و یابس اور ترجمہ در ترجمہ پادریوں وغیرہ کے اپنے خیالات صُحف
سابقہ میں ملے ہوئے ہیں ان کو بھی مَا أُنْزِلَ مِن قَبْلِكَ میں شمار کر لیا جاوے.بلکہ سابقہ اور آئندہ
سب کا معیار ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ ہے اور اسی لئے بِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ سے بھی یہ مقدم ہے.بالآخِرَةِ کے ساتھ مَا اُنْزِل کا کلمہ استعمال نہیں کیا ہے کیونکہ آئندہ مکالمہ الہی کا جس قدر
سلسلہ ہوگا وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہو گا اور مَا اُنْزِلَ النيك سے اس کا وجود الگ نہ ہو
گا.اور چونکہ اس کے ذریعہ سے مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ پر ایک کامل یقین حاصل ہوتا جاوے گا اس لئے
آخرة کے ساتھ يُوقِنُونَ کا لفظ رکھا ہے.اس کا اطلاق خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں خود
200
Page 209
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اس طرح ہوا کہ اس سورت کے بعد اور بھی حصہ قرآن کریم کا
آپ پر نازل ہوا اور صحابہ اس کو مان کر گویا اس آیت پر عامل ہو گئے.آخرةِ اِس کے معنے پیچھے آنے والی بات کے کئے ہیں.کلام الہی پر گفتگو کرتے
ہوئے دکھایا ہے کہ آئندہ مکالمہ الہیہ کی طرف اشارہ ہے.اب اعمال کے لحاظ سے دیکھا
جاوے تو ہر ایک عمل کے بعد جو ایک نتیجہ اس کا ہے اس پر یقین کو ہونا ضروری ہے کیونکہ جب
تک انسان کے دل میں یقینی طور پر یہ بات نہ بیٹھ جاوے کہ میرا ہر ایک عمل خواہ اس کا تعلق
صرف قلب سے ہے یا اس میں اعضاء بھی شامل ہیں ضرور ایک نتیجہ نیک یا بد پیدا کرے گا اور
میری اس عملی تخمریزی پر ثمرات مرتب ہوں گے تب تک گناہ سے رہائی ہر گز ممکن ہی نہیں ہے
اور نجز اس علاج کے اور کوئی علاج گناہ کا نہیں.جب معنی کے اعمال مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ کے موافق اپنے اپنے محل اور موقعہ پر ہوں گے تو اس
کی آخرت یہ ہوگی کہ مرتبہ یقین کا اُسے حاصل ہوگا.البدر 6 فروری 1903 ، صفحہ 23)
أولَئِكَ عَلى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
حمید یہی لوگ ( جن کا اوپر ذکر ہوا) اپنے رب سے ہدایت پر ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جو
مظفر ومنصور ہوں گے.اس سے سابقہ آیات میں متقی کی تعریف اور معنے بیان کر کے اب
اللہ تعالیٰ نے بطور نتیجہ کے بتلا دیا کہ متقیوں کے لئے اس کتاب سے ہدایت پر ہونے کے یہ
معنے ہیں کہ جب انسان ایمان بالغیب رکھ کر اور حقوق الہی اور حقوق العباد کو کما حقہ ادا کر کے
اور خدا تعالیٰ کے کلیم ہونے پر ایمان لا کر اپنے اعمال کے نتائج اور ثمرات پر کامل یقین رکھتا ہے
تو ہر ایک حجاب ڈور ہو کر اس کو کامیابی نصیب ہوتی ہے اور مشقی کے ہدایت پر ہونے کی یہ
ایک دلیل بیان فرمائی ہے کہ اگر وہ کامیاب ہو جاویں تو پھر اُن کی کامیابی ان کے راہ راست
پر ہونے کی دلیل ہے.دعویٰ کر کے دشمن پر ایک خاص غلبہ پانا ایک خاص نشان صداقت کا
ہوتا ہے.201
Page 210
خَتَمَ اللهُ عَلى قُلُوم - ختم کہتے ہیں چھاپے کے ساتھ چھا پہ لگانے کو اور اس اثر کو جو
کہ چھا پہ لگانے سے حاصل ہوتا ہے اور حفاظت اور آخر تک پہنچنے کو.اور قُلُوب قلب کی جمع
ہے اور قلب کہتے ہیں دل کو.اور دل کو قلب اس لئے کہتے ہیں کہ خون کو قلب کرتا ہے.کیونکہ
وہ ایک جانب سے لیتا ہے اور دوسری طرف سے بدن کی طرف بھیجتا ہے یا اس کے تقلب
کے لئے کیونکہ وہ قرار نہیں پکڑتا.اور اسی وجہ سے آنحضرت نے فرمایا ہے الْقَلْبُ بَيْنَ
إصْبَعَى الرَّحْمنِ يُقلِبُهَا كَيْفَ شَاء ( دل رحمن کی دو انگلیوں کے درمیان ہے اُلٹاتا ہے اس کو
جیسا کہ چاہتا ہے )
رسالہ
تعلیم الاسلام ماہ جنوری 1907ء)
خَتَمَ اللهُ عَلى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ
هم کا لفظ یہاں تین بار آیا ہے اور یہ ضمیر جمع مذکر غائب کی ہے جس کے معنے ہیں وہ
لوگ.پس معلوم ہوا کہ یہ ذکر ایسے لوگوں کا ہے جن کا پہلے کوئی ذکر آ چکا ہے.اس لئے ھم
کے معنی سمجھنے کے لئے ضرور ہوا کہ ماقبل کو ہم دیکھ لیں.تو جب ہم نے ماقبل کو دیکھا تو یہ
آیت موجود ہے.اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمُ انْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرُهُمْ لَا
يُؤْمِنُونَ اِس بیان سے اتنا تو معلوم ہوا کہ وہ ایسے منکر لوگ ہیں جن کے لئے ختم اللہ کا
ارشاد ہے.عام نہیں.پھر قرآن کریم نے صاف صاف فرمایا ہے جہاں ارشاد کیا ہے بَلْ طَبَعَ اللهُ عَلَيْهَا
بِكُفْرِهِمْ (النساء 156) یعنی ان کے کفر کے سبب اُن کے دلوں پر مہر لگا دی.اس سے
معلوم ہوا کہ مہر کا باعث کفر ہے انسان کفر کو چھوڑے تو مہر ٹوٹ جاتی ہے.اسی طرح
فرمایا: كَذلِكَ يَطْبَعُ اللهُ عَلى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَيْرٍ جَبَّارٍ (المؤمن 36)
پس تفصیل دونوں آیتوں کی یہ ہے.اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ( تحقیق ان لوگوں نے کفر کیا) یاد
رکھو کہ کفر کرنا کا فرانسان کا اپنا فعل ہے جیسے قرآن کریم نے بتایا اور یہ پہلی بات ہے جو کافر
سے سرزد ہوئی ہے.اور یہ کفر خدا داد روحانی قوتوں، طاقتوں سے کام نہ لینے سے شروع ہوا جو
202
Page 211
دل کی خرابی کا نشان ہے.سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرُهُمْ ) برابر ہو رہا ہے ان کے نزدیک خواہ ڈرایا
ونے یا نہ ڈرایا تونے) یعنی تیرے ڈرانے کی کچھ پرواہ نہیں کرتے.یہ دوسرا فعل کافر
انسان کا ہے کہ اس نے اپنی عقل و فکر سے اتنا کام بھی نہیں لیا.اگر اس میں یہ خوبی نہ تھی کہ
ایمان کے لئے خود فکر کرتا ، سوچتا، عقل سے آپ کام لیتا تو کم سے کم رسول کریم کے بیانات کو
ہی سنتا کہ کفر کا نتیجہ کیسا برا اور اس کفر کا انجام کیسا بُرا ہے.لا يُؤْمِنُونَ.نہیں مانتے.یہ تیسرا فعل کا فرانسان کا ہے.اوّل تو ضرور تھا کہ قلب سے کام لیتا
جو روحانی قوت کا مرکز ہے.اگر اس موقع کو ضائع کر چکا تھا تو مناسب یہ تھا کہ نبی کریم کی باتیں
سنتا.پس کان ہی اس کے لئے ذریعہ ہو جاتے کہ ایماندار بن جاتا.اور یہ دوسرا موقع حصول ایمان
کا تھا.پھر اگر یہ بھی کھو بیٹھا تو مناسب تھا کہ پگے ایمانداروں کے چال چلن کو دیکھتا جو ایسے موقع
پر اسی کے شہر میں موجود تھے اور یہ بات اس کا فر کو آنکھ سے حال ہوسکتی تھی مگر اس نے یہ تیسرا موقع
بھی ضائع کر دیا.غور کرو اگر کوئی دانا حا کم کسی کو مختلف عہدے سپر د کرے لیکن وہ عہدہ دار کہیں بھی
اپنی طاقت سے کام نہ لے تو کیا حاکم کو مناسب نہیں کہ ایسے نکتے شخص کو عہدہ سے اس وقت تک
معزول کر دے جب تک وہ خاص تبدیلی نہ کرے.آب اسی ترتیب سے دوسری آیت پر غور کرو.خَتَمَ اللهُ عَلى قُلُوبِهم - مُہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر.اس لئے کہ انہوں نے
اپنے دل کا ستیا ناس خود کیا اور کفر کیا.وَ عَلَى سَمْعِهِمْ.اور ان کے کانوں پر.یہ دوسری سزا ہے کیونکہ انہوں نے اپنے کانوں سے
کام نہ لیا.وَ عَلى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ.یہ تیسری سزا ہے کہ ان کی آنکھوں پر پٹی ہے کیونکہ انہوں نے
آنکھ سے بھی کام نہ لیا.(ماخوذ از حقائق الفرقان )
203
Page 212
حضرت خلیفہ اسیح الثانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں.اس سورۃ کا نام سورۃ البقرہ ہے.اس سورۃ کے نام کے متعلق جو روایات ہیں ان میں
سے بعض یہ ہیں.ترمذی میں ہے عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكُلِّ شَى
سَنَاهُ وَإِنَّ سَنَامَ الْقُرْآنِ سُوْرَةُ البَقَرَةِ وَفِيهَا آيَةٌ هِيَ سَيْدَةُ أَي القُرْآنِ هِيَ آيَةُ الْكُرْسِى
(ترمذی جلد دوم ابواب فضائل القرآن) یعنی ہر چیز کا ایک چوٹی کا حصہ ہوتا ہے اور
قرآن کریم کی چوٹی کا حصہ سورۃ البقرہ ہے اور اس میں ایک ایسی آیت ہے جو قرآن کریم کی
سب آیات کی سردار ہے اور وہ آیتہ الکرسی ہے.یہ سورۃ مدینہ میں نازل ہوئی ہے اور مختلف وقتوں میں نازل ہوتی رہی ہے اور بعض کے
نزدیک اس کی ایک آیت آخری ایام میں حجتہ الوداع کے موقع پر قربانی کے دن نازل ہوئی
تھی اور وہ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللهِ (بقره (282) کی آیت ہے اس سورۃ کی رباء
کی آیات ( یعنی سود کے احکام پر مشتمل آیات) قرآن کریم کی آخری زمانہ میں نازل ہونے
والی آیات میں سے ہیں.ترمذی نے ابوہریرۃ سے روایت کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فوج
بھیجوائی.جو آدمی اس کے لئے چنے گئے آپ نے اُن سے قرآن کریم سنا.آخر آپ ایک
شخص کی طرف متوجہ ہوئے جو ان سب سے چھوٹی عمر کا تھا اور اس سے پوچھا کہ تم کو کتنا حصہ
قرآن کریم کا یاد ہے؟ اس نے کہاں فلاں فلاں سورۃ کے علاوہ سورۃ بقرہ بھی یاد ہے.آپ
نے فرمایا کہ کیا سورۃ البقرہ تم کو یاد ہے؟ اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ ! آپ نے فرمایا.بس تو
تم اس لشکر کے سردار مقرر کئے جاتے ہو.اس پر اس قوم کے سرداروں میں سے ایک شخص
نے کہا کہ خدا کی قسم میں سورۃ بقرہ کے یاد کرنے سے صرف اس لئے رکا رہا ہوں کہ کہیں مجھے
بعد میں بھول نہ جائے.یہ سن کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن سیکھو اور اسے
پڑھتے رہا کرو کیونکہ جو شخص قرآن سیکھتا ہے اور پھر اسے پڑھتا رہتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے
204
Page 213
اس کی مثال اس تھیلی کی سی ہے جس میں مشک بھرا ہوا ہو اور اس کی خوشبوںکل نکل کر سارے
مکان میں پھیل رہی ہو.اور جو شخص قرآن سیکھ کر سو جائے اس حالت میں کہ قرآن اس کے
اندر ہو اس کی مثال اس تھیلی کی سی ہے جس میں مشک بند پڑا ہو ( ترمذی ابواب فضائل القرآن.ابن ماجہ نے بھی اس روایت کو جز و اروایت کیا ہے )
ابن مردویہ نے عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت کی ہے کہ جس گھر میں سورۃ بقرہ کی تلاوت کی
جائے اس سے شیطان بھاگ جاتا ہے (ابن کثیر )
اسی طرح دارمی نے اپنی مسند میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت درج کی ہے کہ جو
شخص سورۃ بقرہ کی دس آیتیں رات کے وقت پڑھے صبح تک شیطان اس کے گھر میں داخل
نہیں ہوتا.یعنی سورۃ بقرہ کے ابتدا کی چار آیتیں آیتہ الکرسی اور اس کے بعد کی دو آیتیں اور
سورۃ بقرہ سے آخر کی تین آیتیں جو لِلهِ مَا فِي السَّمواتِ کے الفاظ سے شروع ہوتی ہیں.( یہ آخری رکوع ہے جس میں صرف تین آیتیں ہیں ) ( ابن کثیر )
بظاہر سورتوں کے ذاتی فضائل کا ذکر ایک تعلیم یافتہ آدمی پر گراں گزرتا ہے کیونکہ کسی
سورۃ کا صرف سورۃ کے ہونے کے لحاظ سے کوئی خاص اثر رکھنا بے معنی سا معلوم ہوتا ہے لیکن
اگر اس امر کو اس نگہ سے دیکھا جائے کہ ہر سورۃ خاص مضمون پر مشتمل ہوتی ہے اور وہ مضمون
ضرور قلب پر کوئی اثر چھوڑتا ہے تو فضائل کا بیان آسانی سے سمجھ میں آجاتا ہے.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سورۃ بقرہ کے یاد کرنے پر ایک نوجوان کو لشکر کا امیر بنا
دیا.اس میں کئی حکمتیں تھیں.اول آپ نے اس طرح دوسرے لوگوں کے دلوں میں زیادہ سے زیادہ قرآن یاد کرنے اور
یادر کھنے کی خواہش پیدا کی.اسلامی لشکروں کی سرداری مالی لحاظ سے منفعت بخش تھی مگر اپنے
روحانی باپ کی خوشنودی کی جو قدر صحابہ کے دل میں تھی اسے صرف محبت کی چاشنی سے واقف
لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں.دوسرے اس میں یہ بھی حکمت تھی کہ اس زمانہ میں جوسر دارلشکر ہوتا تھا وہی عام طور پر
205
Page 214
امام الصلوۃ بھی ہوتا تھا اور اسی سے لوگ مسائل وغیرہ بھی دریافت کرتے تھے.اور سورۃ بقرہ
میں باقی سب سورتوں سے زیادہ مسائل بیان ہوئے ہیں یہاں تک کہ حضرت ابن العربی
فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استادوں میں سے ایک اُستاد سے سُنا ہے کہ سورۃ بقرہ میں ایک
ہزار حکم ہے اور ایک ہزار مناہی ہے اور ایک ہزار فیصلے اور ایک ہزار خبریں ہیں ( قرطبی) یہ
صوفیانہ رنگ کی بات ہے لیکن اس بات سے انکار نہیں ہو سکتا کہ سورۃ بقرہ میں مضامین کی
نوعیت اور احکام اسلام کی وسعت اس قدر ہے کہ دوسری سورتوں میں سے کسی میں بھی اس قدر
نہیں ہے.یہ جو آپ نے فرمایا کہ جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جائے اس میں شیطان نہیں آتا اس کا
بھی یہی مطلب ہے کہ اس سورۃ میں شیطانی وساوس کا ایسارڈ موجود ہے کہ اس پر غور کرنے کے
بعد شیطان گھر میں نہیں آ سکتا.اور یہ جو فرمایا کہ صبح تک شیطان نہیں آتا اس سے اس طرف
اشارہ کیا کہ تعلیم خواہ کیسی اعلیٰ ہو جب تک بار بار دہرائی نہ جائے دل پر پورا اثر نہیں ہوتا اور
نیک اثر خواہ کس قدر اعلیٰ ہو کچھ عرصہ کے بعد اگر اس کی تجدید نہ کی جائے زائل ہو جاتا ہے.اور یہ جو فرمایا کہ جو شخص سورۃ بقرہ کی پہلی چار آیتیں اور آیۃ الکرسی اور اس کے ساتھ کی
دو آیتیں اور سورۃ بقرہ کی آخری تین آیتیں پڑھے اس کے گھر سے بھی شیطان بھاگ جاتا
ہے.اس سے بھی یہی مراد ہے کہ ان آیتوں میں اسلام کا خلاصہ ہے.سورہ بقرہ کی پہلی آیتوں
میں پاک عملی زندگی کا نقشہ کھینچا گیا ہے.آیتہ الکرسی میں صفات باری کا نہایت لطیف نقشہ ہے
اور سورۃ بقرہ کی آخری آیتوں میں دل کو پاک کر دینے والی دُعائیں ہیں اور یہ تین چیزیں یعنی
(1) الہی کلام کی تتبع میں نیک اعمال کا بجالانا (2) صفات الہیہ پر غور کرنا ( 3 ) اور ان دونوں
باتوں کے ساتھ دعا میں مشغول رہنا اور اپنے آپ کو آستانہ الہی پر گرادینا.جب اکٹھی ہو جائیں
تو انسان کا دل پاک ہو جاتا ہے اور شیطان بھاگ جاتا ہے.کیا سورۃ فاتحہ کا تعلق تو کلام الہی کا خلاصہ ہونے کے وجہ سے سب ہی سورتوں سے ہے لیکن
206
Page 215
سورۃ بقرہ کو چونکہ اس کے معا بعد رکھا گیا ہے اس سورۃ کا تعلق سورۃ فاتحہ سے یقیناً سب سے
زیادہ ہے.چنانچہ اول تعلق تو اس کا اس سے یہ ہے کہ جس طرح سورۃ فاتحہ خلاصہ ہے سارے
قرآن کریم کا.اسی طرح یہ سورۃ بھی خلاصہ ہے سب قرآن کا کیونکہ اس میں دلائل و براہین بھی
بیان کئے گئے ہیں.شریعت بھی اور فلسفۂ شریعت بھی.اور پاکیزگی اور طہارت کے گر بھی بیان
کئے گئے ہیں.اور ابراہیمی دُعا میں آخری موعود کی بعثت کا یہی مقصد بیان کیا گیا ہے.دوسرا تعلق سورۃ فاتحہ کا سورۃ بقرہ سے یہ ہے کہ اس میں اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کی
دعا سکھائی گئی تھی اور سورۃ بقرہ کی ابتدا بھی آیت ذلك الْكِتَبُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى
لِلْمُتَّقِین سے ہوئی ہے یعنی یہ سورۃ صراط مستقیم کی طرف لے جانے کے مقصد کو پورا کرتی
ہے اور فاتحہ کی دُعا کی قبولیت کا ظاہری نشان ہے.الم
چونکہ یہ حروف الگ الگ بولے جاتے ہیں انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں جو ایک سے
لے
کر پانچ کی تعداد تک بعض سورتوں کے شروع میں بیان کئے گئے ہیں.حروف کی اقسام کے
لحاظ سے یہ چودہ حرف ہیں اور ان کی تفصیل یہ ہے ا.ل.م.ص.رک.ہی.ع.ط.س.ح.ق.ن.ان میں سے ق اور نون اکیلا اکیلا ایک سورۃ کے پہلے آیا ہے.باقی دودویا
زیادہ مل کر آئے ہیں.ان کے معنوں کے بارہ میں مفسرین میں بہت اختلاف ہے.بعض نے تو لکھا ہے کہ یہ
حروف خدا تعالیٰ کے اسرار میں سے ہیں اس لئے ان کے معنوں کے پیچھے نہیں پڑنا چاہئے.بعض نے لکھا ہے کہ ان سے یہ مراد ہے کہ قرآن کریم بھی حروف ہجاء سے بنا ہے مگر پھر بھی
معجزانہ کلام ہے.اگر یہ انسانی کلام ہوتا تو کیوں عرب انہی حروف سے ایسا ہی کلام نہ بنا لیتے.بعض نے کہا ہے کہ یہ سورتوں کے نام ہیں.بعض نے کہا ہے کہ یقسمیں ہیں جو سورۃ کے مضمون
پر اللہ تعالیٰ نے کھائی ہیں.مگرسب
مطالب ایسے معمولی ہیں کہ ان کی خاطر حروف مقطعات کا قرآنی سور کے شروع میں رکھنا نظر
207
Page 216
میں جچتا نہیں.بعض نے ان کو با معانی کلام کا خلاصہ قرار دیا ہے.مثلاً الف لام میم کے معنے یہ کئے ہیں کہ اللہ ، جبریل ، محمد.یعنی اللہ تعالیٰ نے جبریل کے
ذریعہ سے محمد ( صلی اللہ علیہ وسلم) پر یہ کلام نازل کیا ہے.یہ معنے الف لام میم کے حروف
پر تو چسپاں ہو جاتے ہیں.لیکن تمام حروف مقطعات کی اس طرح تشریح نہیں ہوسکتی.بعض نے ان حروف کے معنی یہ کئے ہیں کہ ان میں اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا ذکر ہے جن کی
تشریح بعد کی سورۃ میں کی گئی ہے اور صفات کے پہلے حروف یا بعض اہم حروف کو مضمون کی
طرف اشارہ کرنے کے لئے بیان کر دیا گیا.جیسا کہ میں آگے چلے کر بیان کروں گا یہی معنی سب سے زیادہ درست اور شانِ قرآن اور
شہادتِ قرآن کے مطابق ہیں.بعض نے ان حروف سے ان آیات کے مضامین کے اوقات کی طرف اشارہ مراد لیا ہے.یعنی حروف مقطعات سے جس قدر عدد نکلتے ہیں اس قدر عرصہ تک کے متعلق ان سورتوں میں
واقعات بیان کئے گئے ہیں.یا یہ کہ اس زمانہ کے حالات کی طرف ان سورتوں میں خاص طور پر
اشارہ کیا گیا ہے.یہ معنی بھی جیسا کہ بتایا جائے گا درست معلوم ہوتے ہیں اور رسول کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی کم سے کم ان کی تصدیق کرتی ہے.اس امر کا ثبوت کہ ان حروف کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی وحی کا حصہ
قرار دیا ہے.اس حدیث سے ملتا ہے جو بخاری نے اپنی کتاب تاریخ میں نیز ترمذی اور حاکم
نے عبد اللہ بن مسعود سے نقل کی ہے.وہ فرماتے ہیں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ رسول کریم
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن کریم کا ایک حرف بھی
پڑھے وہ جنت کا مستحق ہوگا اور اس کی یہ نیکی دس گنے ثواب کا مستحق اسے بنادے گی.اور میں یہ
نہیں کہتا کہ الٹ ایک حرف ہے.بلکہ الٹر کا الف ایک مستقل حرف ہے اور لام ایک
مستقل حرف ہے اور میم ایک مستقل حرف ہے.208
Page 217
میں نے ایک معنی ان حروف کے یہ بتائے تھے کہ ان کے عدد کے مطابق سالوں کے
واقعات کی طرف ان کے بعد کی سورۃ میں اشارہ کیا گیا ہے.یہ معنی ایک یہودی عالم نے کئے
تھے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نے ان کو دہرایا.آپ نے اس کی تردید
نہیں کی بلکہ ایک رنگ میں تصدیق کی.اس لئے یہ معنی بھی قابل غور ضرور ہیں اور تدبر کرنے
والوں کے لئے اس تفسیر سے کئی نئے مطالب کی راہ کھل جاتی ہے.وہ حدیث جس میں اس
تشریح کا ذکر آتا ہے یوں ہے.ابن اسحاق نے اور بخاری نے ( اپنی تاریخ میں ) نیز ابن
جریر نے ابن عباس سے اور انہوں نے جابر بن عبد اللہ سے یوں روایت کی ہے کہ ابو یا سر بن
اخطب ( رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں مشہور یہودی علماء میں سے تھا) کچھ یہود
سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا جبکہ آپ سورۃ بقرہ کی ابتدائی آیات پڑھ
رہے تھے یعنی الهم ذلك الكتبُ لَا رَيْبَ فِيهِ.وہ یہ سن کر اپنے بھائی حیی بن اخطب کے
پاس جبکہ وہ یہود کی ایک جماعت کے پاس بیٹھا ہوا تھا آیا اور کہا تم کو کچھ معلوم ہے میں نے
محمد ( رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ) کو کیا پڑھتے سنا ہے؟ خدا کی قسم میں نے سنا ہے کہ وہ اپنے
اوپر نازل ہونے والے کلام میں سے یہ کلام پڑھ رہے تھے الم ذلِكَ الْكِتب اس پر
محقیقی نے کہا کیا فی الواقع تم نے یہ کلام سنا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں اس پر حقیقی اپنے
ساتھیوں کو لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اے محمد ( صلے اللہ علیہ وسلم )
کیا آپ کے متعلق یہ بات نہیں کہی جاتی کہ آپ اپنے اوپر نازل ہونے والے کلام میں سے
ایک یہ وحی بھی سناتے ہیں کہ العمر ذلك الكتب.آپ نے فرمایا یہ درست ہے.اس نے
کہا کیا یہ کلام جبریل نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر نازل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں.حینی نے کہا کہ آپ سے پہلے بھی انبیاء آئے ہیں ہمیں معلوم نہیں کہ سوائے آپ کے ان
میں سے کسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی حکومت کی مدت اور اس کی قوم کا عرصہ بیان کیا ہو.پھر اس نے اپنے ساتھیوں کو مخاطب کیا اور کہا الف کا ایک لام کے تیس اور میم کے
چالیس.یعنی گل اکہتر سال ہوئے.کیا تم ایسے نبی کے دین کو قبول کرو گے جس کی حکومت کا
209
Page 218
عرصہ اور جس کی اُمت کا زمانہ گل اکہتر سال ہے.پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف
مخاطب ہوا اور پوچھا کہ اے محمد ( صلے اللہ علیہ وسلم ) کیا ان کے علاوہ اور حرف بھی آپ پر نازل
ہوئے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں.اس نے پوچھا کیا؟ آپ نے فرمایاالتص.اس نے کہا
ی زیادہ گراں ہے اور لمبا عرصہ ہے.الف کا ایک ، لام کے تیس، میم کے چالیس.اور ص کے
تؤے.گل ایک سوا کا سٹھ (161) ہوئے.پھر پوچھا کیا ان کے سوا اور حروف بھی آپ پر
نازل ہوئے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں.اس نے کہا وہ کیا؟ آپ نے فرمایا الر.اس نے کہا
یہ اس سے بھی زیادہ گراں اور لمبا عرصہ ہے.الف کا ایک لام کے تیس اور د کے دوسو.گل
دوسو اکتیس ہوئے.پھر کہنے لگا کیا ان کے سوا اور حروف بھی ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں.اور وہ
الٹر کے حروف ہیں.اس پر وہ بولا کہ یہ تو پہلے سے بھی گراں اور لمبا عرصہ ہے.الف کا ایک.لام کے تیں.میم کے چالیسں.اور رکے دوسو ہوئے.کل دوسوا کہتر سال کا عرصہ ہوا.م
پھر کہنے لگا اے محمد ( صلے اللہ علیہ وسلم ) ! آپ کا معاملہ ہم پر مشتبہ ہو گیا ہے.پتہ نہیں لگتا آپ
کو لمبی عمر عطا ہوئی ہے یا چھوٹی.پھر وہ اور اس کے ساتھی اُٹھ کر چلے گئے.راستہ میں ابو
یاسر نے اپنے بھائی اور دوسرے یہودی علماء سے کہا کیا معلوم کہ یہ سب زمانے محمد ( صلے اللہ
علیہ وسلم) کے لئے اکٹھے کر دئیے گئے ہوں جن کی میزان سات سو چونتیس سال ہوتی ہے.اس
پرسب نے کہا کہ معاملہ کچھ مشتبہ ہی ہو گیا ہے.اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہود نے ان حروف سے سالوں کی تعداد مُراد لی تھی اور
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے خیال کا اظہار بھی کیا تھا اور آپ نے ان کے خیال
کی تردید نہیں فرمائی.یہود کا یہ خیال کہ ان حروف سے امت محمدیہ کا زمانہ بتایا گیا ہے ایک بالبداہت غلط بات
ہے.کیونکہ امت محمدیہ کا زمانہ تو تا قیامت ہے.لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تردید نہ کرنا
بھی کچھ معنے ضرور رکھتا ہے اور اس کو مدنظر رکھتے ہوئے اور سورتوں کے مضامین کو دیکھتے
ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ حروف اپنی عددی قیمت کے لحاظ سے اس زمانہ کی طرف اشارہ
210
Page 219
کرتے ہیں جس کے واقعات خاص طور پر اس سورۃ میں بیان کئے گئے ہیں جس کی ابتدا میں وہ
حروف آئے ہیں.خواہ اس لحاظ سے کہ بعثت نبوی کے بعد اتنے عرصہ کے اختتام پر وہ
واقعات شروع ہوئے یا اس لحاظ سے کہ اس عرصہ کے اختتام پر وہ واقعات شروع ہوئے.اگر اس خیال کو درست سمجھا جائے تو یہ بات تو واضح ہے کہ سورۃ بقرہ کے واقعات بعثت کے
بعد کے اکہتر سال کے واقعات کا مختصر خاکہ ہیں.حضرت معاویہ 60 ہجری میں فوت ہوئے
ہیں.اس میں تیرہ سال قبل ہجرت کے شامل کئے جائیں تو یہ 73 ہجری ہوتا ہے.یزید کی
بیعت حضرت معاویہ نے وفات سے ایک دو سال پہلے لی ہے.چونکہ اسی وقت سے اصل فتنہ
شروع ہوا ہے اس لئے ابتدائے اسلام اور ترقی اسلام کا زمانہ اکہتر سال ہوتا ہے اور اسی زمانہ
کا نقشہ سورۃ بقرہ میں کھینچا گیا ہے.دوسری سورۃ مریم ہے اس سے پہلے کھیعص کے الفاظ
ہیں جن کی مجموعی رقم 195 ہوتی ہے.سورۃ مریم میں مسیحیت کی ترقی کا ذکر ہے اور خصوصاً دوسری
ترقی کا جو اسلامی ترقی کے بعد ہوئی تھی.تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سال سے مسیحیت نے
دوبارہ سر نکالا ہے.یہی سال ہے جس میں اسلامی تاریخ میں پہلی دفعہ کوشش کی گئی کہ جس
وقت معتصم باللہ مسیحی رومی حکومت کے خلاف لڑ رہا تھا اسے معزول کر کے عباس بن مامون کو
خلیفہ مقرر کر دیا جائے اور اس طرح مسیحیوں کے مقابل پر اسلام کو ضعف پہنچایا جائے.اسی
زمانہ کے قریب مسیحیوں نے دوبارہ سپین پر حملہ کر کے اس کے کچھ حصے واپس لے لئے اور اسی
زمانہ کے قریب یہ بدبختی کا واقعہ دیکھنے میں آیا کہ خلافت اندلس نے خلافت عباسیہ کے
خلاف روما کے عیسائی بادشاہ سے خفیہ معاہدہ کیا اور عباسی حکومت نے شاہ فرانس سے سپین کی
اسلامی حکومت کے خلاف دوستانہ تعلقات قائم کئے اور اس طرح اسلامی سیاست میں مسیحیوں کو
داخل کر کے مسیحیت کی ترقی اور اسلام کے تنزل کی داغ بیل ڈالی.میری رائے میں اگر دوسری
سورتوں پر بھی غور کیا جائے تو زمانہ کے لحاظ سے کافی روشنی ان مضامین پر پڑے گی.اب میں حروف مقطعات کے بارہ میں وہ تحقیق لکھتا ہوں جس کی بنیاد حضرت ابن عباس نے
اور حضرت علی کے کئے ہوئے معنوں پر ہے اور وہ تحقیق یہ ہے.211
Page 220
حروف مقطعات اپنے اندر بہت سے راز رکھتے ہیں.ان میں سے بعض راز بعض ایسے
افراد کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں جن کا قرآن کریم سے ایسا گہرا تعلق ہے کہ ان کا ذکر قرآن کریم
میں ہونا چاہیئے.لیکن اس کے علاوہ یہ الفاظ قرآن کریم کے بعض مضامین کے لئے قفل کا بھی
کام دیتے ہیں.کوئی پہلے ان کو کھولے تب ان مضامین تک پہنچ سکتا ہے.جس جس حد تک ان
کے معنوں کو سمجھتا جائے اسی حد تک قرآن کریم کا مطلب کھلتا جائے گا.میری تحقیق یہ بتاتی ہے کہ جب حروف مقطعات بدلتے ہیں تو مضمون قرآن جدید ہو جاتا
ہے.اور جب کسی سورۃ کے پہلے حروف مقطعات استعمال کئے جاتے ہیں تو جس قدر سورتیں
اس کے بعد ایسی آتی ہیں جن کے پہلے مقطعات نہیں ہوتے ان میں ایک ہی مضمون ہوتا
ہے.اسی طرح جن سورتوں میں وہی حروف مقطعات دُہرائے جاتے ہیں وہ ساری سورتیں
مضمون کے لحاظ سے ایک ہی لڑی میں پروئی ہوئی ہوتی ہیں.اس قاعدہ کے مطابق میرے نزدیک سورۂ بقرہ سے لے کر سورہ تو بہ تک ایک ہی مضمون
ہے اور یہ سب سورتیں اللہ سے تعلق رکھتی ہیں.سورۃ بقرہ اللہ سے شروع ہوتی ہے.پھر سورۃ
آل عمران بھی اللہ سے شروع ہوتی ہے.پھر سورہ نساء ،سورہ مائدہ اور سورہ انعام حروف
مقطعات سے خالی ہیں اور اس طرح گویا پہلی سورتوں کے تابع ہیں جن کی ابتدا الٹر سے ہوتی
ہے.ان کے بعد سورہ اعراف المص سے شروع ہوتی ہے اس میں بھی وہی اللہ موجود ہے
ہاں حرف ص کی زیادتی ہوئی ہے.اس کے بعد سورۃ انفال اور براء ۃ حروف مقطعات سے
خالی ہیں.پس سورۃ براءة تک الھم کا مضمون چلتا ہے.سورۃ اعراف میں جوص بڑھایا گیا
اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حرف تصدیق کی طرف لے جاتا ہے.سورہ اعراف، انفال اور تو بہ میں
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی اور اسلام کی ترقی کا ذکر کیا گیا ہے.سورۃ اعراف میں
اصولی طور پر اور انفال اور تو بہ میں تفصیلی طور پر تصدیق کی بحث ہے اس لئے وہاں ص کو بڑھا
دیا گیا ہے.سورۃ یونس سے اللہ کی بجائے الر شروع ہو گیا ہے ال تو وہی رہا اور ھر کو بدل کر د کر دیا.212
Page 221
پس یہاں مضمون بدل گیا.اور فرق یہ ہوا کہ بقرہ سے لے کر تو بہ تک تو علمی نقطہ نگاہ سے بحث کی
گئی ہے اور سورۃ یونس سے لے کر سورۃ کہف تک واقعات کی بحث کی گئی ہے اور واقعات
کے نتائج پر بحث کو منحصر رکھا گیا ہے.اس لئے فرمایا کہ الر یعنی آنا اللہ آری میں اللہ ہوں جو
سب کچھ دیکھتا ہوں اور تمام دنیا کی تاریخوں پر نظر رکھتے ہوئے اس کلام کو تمہارے سامنے
رکھتا ہوں.غرض ان سورتوں میں رؤیت کی صفت پر زیادہ بحث کی گئی ہے اور پہلی سورتوں میں
علم کی صفت پر زیادہ بحث تھی.میں فی الحال اس جگہ اختصارا اتنی بات کہہ دینا چاہتا ہوں کہ حروف مقطعات کے متعلق
بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ بے معنی ہیں اور انہیں یونہی رکھ دیا گیا ہے.مگر ان لوگوں کی
تردید خودحروف مقطعات ہی کر رہے ہیں.چنانچہ جب ہم تمام قرآن پر ایک نظر ڈال کر یہ
دیکھتے ہیں کہ کہاں کہاں حروف مقطعات استعمال ہوئے ہیں تو ان میں ایک ترتیب نظر آتی
ہے.سورۃ بقرہ اللہ سے شروع ہوتی ہے.پھر سورہ آل عمران العمر سے شروع ہوتی ہے.پھر سورۃ نساء، سورۂ مائدہ، سورہ انعام حروف مقطعات سے خالی ہیں.پھر سورۃ اعراف المص
سے شروع ہوتی ہے اور سورۃ انفال اور براءۃ خالی ہیں.ان کے بعد سورۃ یونس، سورۃ ہود،سورۃ
یوسف، الر سے شروع ہوتی ہیں اور سورہ رعد میں م بڑھا کر المر کر دیا گیا ہے.لیکن جہاں
المص میں ص آخر میں رکھا یہاں مہ کو دسے پہلے رکھا گیا ہے.حالانکہ اگر کسی مقصد کو
مد نظر رکھے بغیر زیادتی کی جاتی تو چاہئے تھا کہ میم کو جوزائد کیا گیا تھار کے بعد رکھا جاتا.میم کوالڑ کے درمیان رکھ دینا بتاتا ہے کہ ان حروف کے کوئی خاص معنے ہیں اور جب ہم
دیکھتے ہیں کہ پہلے اللہ کی سورتیں ہیں.اور اس کے بعد الر کی.تو صاف طور پر معلوم ہو جاتا
ہے کہ مضمون کے لحاظ سے میم کو رپر تقدم حاصل ہے اور سورۃ رعد جس میں میم اور ر
اکٹھے کر دیے گئے ہیں اس میں میم کو رسے پہلے رکھنا اس امر کو واضح کر دیتا ہے کہ یہ سب
حروف خاص معنے رکھتے ہیں.اسی وجہ سے ان حروف کو جو معنی تقدم رکھتے ہیں ہمیشہ مقدم ہی
رکھا جاتا ہے.سورۃ رعد کے بعد ابراہیم اور حجر میں اگر استعمال کیا گیا ہے لیکن محل، بنی اسرائیل
اور کہف میں مقطعات استعمال نہیں ہوئے.اور یہ سورتیں گویا پہلی سورتوں کے مضامین کے
213
Page 222
تابع ہیں.ان کے بعد سورۃ مریم ہے جس میں کھیعص کے حروف استعمال کئے گئے ہیں.سورۃ مریم کے بعد سورۃ طہ ہے اور اس میں طہ کے حروف استعمال کئے گئے ہیں.اس کے بعد
انبیاء، حج، مومنون ، نور اور فرقان میں حروف مقطعات چھوڑ دیئے گئے ہیں.گویا یہ سورتیں طہ
کے تابع ہیں.آگے سورہ شعراء طسم سے شروع کی گئی ہے.گو یاطاء کو قائم رکھا گیا ہے
اور ھا کی جگہ س اور میم لائے گئے ہیں.اس کے بعد سورہ نمل ہے جو طس سے شروع ہوتی
ہے اس میں سے میھ کو اڑادیا گیا ہے اور طاء اور اس قائم رکھے گئے ہیں.اس کے بعد سورۃ
قصص کی ابتدا پھر طسم سے کی گئی ہے گویا میم کے مضمون کو پھر شامل کرلیا گیا ہے.اس
کے بعد سورہ عنکبوت کو پھر اللہ سے شروع کیا گیا ہے اور دوبارہ علم الہی کے مضمون کو نئے
پیرایہ اور نئی ضرورت کے ماتحت شروع کیا گیا ہے (اگرچہ میں ترتیب پر اس وقت بحث نہیں
کر رہا.لیکن اگر کوئی کہے کہ اللہ دوبارہ کیوں لایا گیا ہے.تو اس کی وجہ یہ ہے کہ سورۃ بقرہ
سے الم کے مخاطب کفار تھے اور یہاں سے العد کے مخاطب مومن ہیں ) سورۃ عنکبوت کے
بعد سورة روم، سورة لقمان اور سورہ سجدہ کو بھی اللہ سے شروع کیا گیا ہے ان کے بعد سورۃ
احزاب.سبا.فاطر.بغیر مقطعات کے ہیں اور گویا پہلی سورتوں کے تابع ہیں.ان کے بعد سورۃ
لیس ہے جس کو لیس کے حروف سے شروع کیا گیا ہے.اس کے بعد سورۃ طفت بغیر
مقطعات کے ہے.اس کے بعد سورہ ص حرف ص سے شروع کی گئی ہے پھر سورہ زمر
حروف مقطعات سے خالی اور پہلی سورۃ کے تابع ہے.اس کے بعد سورہ مومن لحم سے شروع
کی گئی ہے.اس کے بعد سورہ حم السجدہ کو بھی خم سے شروع کیا گیا ہے.پھر سورۃ
شوری کو بھی ختم سے شروع کیا گیا ہے.لیکن ساتھ حروف عشق بڑھائے گئے ہیں.اس کے
بعد سورۃ زُخرف ہے اس میں بھی ختم کے حروف ہی استعمال کئے گئے ہیں.پھر سورۂ دخان،
جاثیہ اور احقاف بھی خم سے شروع ہوتی ہیں.ان کے بعد سورۃ محمد، فتح اور حجرات بغیر مقطعات
کے ہیں اور پہلی سورتوں کے تابع ہیں.سورہ ق حرف ق سے شروع ہوتی ہے اور قرآن کریم
کے آخر تک ایک ہی مضمون چلا جاتا ہے.یہ ترتیب بتا رہی ہے کہ یہ حروف یونہی نہیں رکھے گئے.پہلے العد آتا ہے پھر المص آتا
214
Page 223
ہے جس میں ص کی زیادتی کی جاتی ہے.پھر اتر آتا ہے اور پھر المر آتا ہے کہ جس
میں میم کی زیادتی کی جاتی ہے پھر کھیعص آتا ہے جس میں ص پر چار اور حروف کی
زیادتی ہے پھر طلہ لایا جاتا ہے.اور پھر اس میں کچھ تبدیلی کر کے طلسم کر دیا جاتا ہے.ایک ہی قسم کے الفاظ کا متواتر لانا اور بعض کو بعض جگہ بدل دینا بعض جگہ اور رکھ دینا بتا تا ہے
که خواه یہ حروف کسی کی سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں جس نے انہیں رکھا ہے کسی مطلب کے لئے ہی
رکھا ہے.اگر یونہی رکھے جاتے تو کوئی وجہ نہ تھی کہ کہیں ان کو بدل دیا جاتا، کہیں زائد کر دیا
جاتا، کہیں کم کر دیا جاتا.علاوہ مذکورہ بالا دلائل کے خود مخالفین اسلام کے ہی ایک استدلال سے یہ مستنبط ہوتا ہے کہ
مقطعات کچھ معنی رکھتے ہیں.مخالفین اسلام کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی سورتوں کی ترتیب ان کی
لمبائی اور چھوٹائی کے سبب سے ہے.اب اگر یہ صحیح ہے تو کیا یہ عجیب بات نہیں کہ باوجوداس
کے کہ سورتیں اپنی لمبائی اور چھوٹائی کے سبب سے آگے پیچھے رکھی گئی ہیں ایک قسم کے حروف
مقطعات اکٹھے آتے ہیں.العہ کی سورتیں اکٹھی آگئی ہیں.الر کی اکٹھی.طہ اور اس
کے مشترکات کی اکٹھی.پھر اللہ کی اکٹھی.ختم کی اکٹھی.اگر سورتیں ان کے حجم کے
مطابق رکھی گئی ہیں تو کیا یہ عجیب بات نہیں معلوم ہوتی کہ حروف مقطعات ایک خاص حجم پر
دلالت کرتے ہیں.اگر صرف یہی تسلیم کیا جائے تب بھی اس کے معنے یہ ہوں گے کہ حروف
مقطعات کے کچھ معنی ہیں.خواہ یہی معنی ہوں کہ وہ سورۃ کی لمبائی اور چھوٹائی پر دلالت کرتے
ہیں.مگر حق یہ ہے کہ ایک قسم کے حروف مقطعات کی سورتوں کا ایک جگہ پر جمع ہونا بتا تا ہے کہ
ان کے معنوں میں اشتراک ہے اور یہ حروف سورتوں کے لئے بطور کنجیوں کے ہیں.حروف مقطعات کی نسبت یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ اس غیر معمولی طریق کو قرآن کریم نے
کیوں استعمال کیا؟ کیوں نہ یہی مضمون سیدھی سادھی عبارت میں بیان کر دیا تا کہ اول عربوں پر
اور بعد میں دوسرے لوگوں پر اس کا سمجھنا آسان ہوتا تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ غیر معمولی طریق
215
Page 224
نہیں بلکہ عربوں میں یہ طریق کلام رائج تھا اور ان کے بڑے بڑے شاعر بھی اسے استعمال
کرتے تھے اور نثر میں بھی اس کا استعمال ہوتا تھا.( مقطعات کے بارہ میں مزید تفصیلات کے لئے ملاحظہ ہو تفسیر کبیر ازحضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ)
ذلِكَ الْكِتَبُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ.ذلک.اسم اشارہ ہے اور اشارہ بعید کے لئے آتا ہے جس کا ترجمہ اردو میں وہ ہے لیکن کبھی
ھذا کے معنوں میں یعنی قریب کی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لئے بھی استعمال کر لیا جاتا ہے
چنانچہ زجاج کا قول ہے ذلِك الكتب الى هذا الكتب عنى ذلك الكتب کے معنی ہیں یہ
کتاب ( تاج العروس ) لیکن ذلک کو اشارہ بعید کے لئے تصور کرتے ہوئے بھی ذلت کے معنی
یڈ کے کئے جاسکتے ہیں کیونکہ کبھی قریب کی چیز کے لئے دُور کا اشارہ اس کے فاصلہ کی دوری
کے اظہار کے لئے نہیں بلکہ اس کی شان کی بلندی کے اظہار کے لئے بھی استعمال کر دیا جاتا
ہے (فتح البیان)
الكتب - ال اور کتاب کا مجموعہ ہے اور معنوں کے علاوہ ال حرف تعریف بھی ہے اس
صورت میں یہ کبھی عہد کے لئے ہوتا ہے اور کبھی جنس کے لئے.جب عہد کے لئے ہو تو کبھی
ذکری ہوتا ہے اور کبھی ذہنی اور کبھی حضوری.یعنی جس لفظ پر ال آئے کبھی تو اس سے یہ بتانا
مقصود ہوتا ہے کہ یہ وہی امر ہے جس کا ذکر کر آئے ہیں.اور کبھی یہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ ہماری
مُراداس چیز سے ہے جو ہم اور تم دونوں اپنے دلوں میں جانتے ہیں.اور کبھی یہ بتانا مقصود ہوتا
ہے کہ یہ جو سامنے چیز پڑی ہے میں اسی کا ذکر کر رہا ہوں.اور جب جنسی ہو تو استغراقی ہوتا
ہے.یعنی اس سے یہ مراد ہوتی ہے کہ اس جنس کے سب افراد اس لفظ میں شامل ہیں.استغراقی آگے کبھی حقیقی ہوتا ہے جیسے خُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا.انسان ضعیف ہی پیدا کئے
گئے ہیں اور کبھی مجازی مجازی کی صورت میں ال لا کر یہ بتایا جاتا ہے کہ کامل فرد یہی ہے ورنہ
حقیقتاً اس قسم کے اور افراد بھی موجود ہوتے ہیں.216
Page 225
کتاب کتاب.کتب کا مصدر ہے اور اسی لحاظ سے ہر اس چیز کا نام کتاب رکھا گیا ہے
جس میں مختلف مسائل کو فصل ، باب کے ساتھ لکھ دیا جائے.تو رات کو بھی انہی معنوں میں
کتاب کہتے ہیں اور ہر لکھی ہوئی تصنیف کو بھی کتاب کہتے ہیں.اور کتاب کے معنی فرض کے
بھی ہیں اور حکم کے بھی اور قضاء آسمانی کے بھی.اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والے
کلام کو بھی کتاب کہتے ہیں اور خط کو بھی کتاب کہتے ہیں ( اقرب)
پس اس لفظ کے اپنے اپنے محل پر مختلف معنی ہوں گے کبھی فروض و احکام کو مدنظر رکھتے
ہوئے شریعت والی وحی کو کتاب کہیں گے اور کبھی صرف الہام کو مدنظر رکھتے ہوئے ہر قطعی اور
یقینی وحی کو کتاب کہیں گے خواہ کتابی صورت میں جمع کی گئی ہو یا نہ کی گئی ہو.ريب الظُّئَةُ وَالتهمة تخمین سے بلا دلیل کوئی بات کہنا یا محض وہم سے کسی پر الزام لگانا
اور اس کی سچائی میں شبہ کرنا.الشك- شک- الْحَاجَةُ -
کمی.ضرورت.اور ریبُ الْمَنُونِ کے
معنے ہیں زمانہ کے مصائب آفات (اقرب)
ریب کا لفظ قرآن کریم میں اور کئی جگہ استعمال ہوا ہے مثلاً اسی سورۃ میں فرماتا ہے وَان
كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مَا نَزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوْ بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ (بقرہ 24) اس جگہ مراد صداقت
میں شبہ کے ہیں.اسی طرح سورۃ حج میں ہے یا اَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ
(الحج 6) اس جگہ بھی بعث بعد الموت کی صداقت میں شک وشبہ کرنے کے معنے ہیں.پھر سورۃ
طور میں ہے اَمَ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ (الطور (31) یعنی کیا نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن یہ کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے جس کے متعلق ہم انتظار کر رہے ہیں کہ
زمانہ کے مصائب آخر اسے ہلاک کر دینگے.اس جگہ ریب مصائب دہر اور ہلاکت کے
معنوں میں مستعمل ہوا ہے.قرآن کریم میں ریب کا لفظ اچھے معنوں میں استعمال نہیں ہوتا.مثلاً فرماتا ہے.مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُرِيبٍ (26) نیکی سے بہت روکنے والا.حد سے بڑھنے والا.شک و
217
Page 226
شبہ کا شکار دوزخ میں ڈالا جائے گا.اسی طرح سورۃ مومن میں آتا ہے كَذلِكَ يُضِلُّ اللهُ مَنْ
هُوَ مسْرِفُ مرتاب (المومن (35) یعنی اللہ تعالیٰ اسی طرح گمراہ قرار دیتا ہے یا بلاک کرتا ہے
اسے جو حد سے بڑھنے والا یا اپنے عقیدہ اور خیالات کی بنیاد غیر معقول شبہات و وساوس پر رکھنے
والا ہو.پس ریب اس شک کو نہیں کہتے جو علم کی زیادتی کا موجب ہوتا ہو اور تحقیق میں مد ہو بلکہ
اس شک کو کہتے ہیں جو تعصب یا بدظنی کی وجہ سے ہو اور سچائی سے محروم کر دے چنانچہ دوسری
جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أوتُوا الْكِتَب وَالْمُؤْمِنُونَ (المدثر (32) ہم
نے یہ (مذکورہ بالا) کام اس لئے کیا ہے کہ تا اہل کتاب اور مومن ریب میں نہ پڑیں گویا
مومن ریب میں نہیں پڑتا اور اللہ تعالیٰ مومن کو ریب سے بچاتا ہے حدیث میں آتا ہے دَغ
مايُرِيبُكَ الى مالا يُرِيبُكَ (ترمذی مطبوعه مطبع مجتبائی جلد دوم صفحه 4 7
ابواب صفة القيامة) یعنی جو چیز تیرے دل میں قلق اور وسوسہ پیدا کرے اسے چھوڑ دے اور
اس چیز کو اختیار کر جس کے بارہ میں وسوسہ نہ ہو.اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ریب
اس شک کو کہتے ہیں جس کی بنیاد وسوسہ اور وہم پر ہو اور اس شک کو نہیں کہتے جو تحقیق و تدقیق
کے لئے ضروری ہوتا ہے.هُدًى - الرشاد سیدھے راستہ پر ہونا.البیان بیان کرنا.الل لاله کسی امر کی طرف
رہبری کرنا ( اقرب)
قرآن کریم میں تقویٰ کا جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کے بارہ میں حضرت ابو ہریرہ سے کسی
نے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ کانٹوں والی جگہ پر سے گزرو تو کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا
یا اس سے پہلو بچا کر چلا جاتا ہوں یا اس سے پیچھے رہ جاتا ہوں یا آگے نکل جاتا ہوں.انہوں نے
کہا کہ بس اسی کا نام تقویٰ ہے.یعنی انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے مقام پر کھڑا نہ ہو اور ہر
طرح اس جگہ سے بچنے کی کوشش کرے.ذلِكَ الْكِتَابُ کے کئی معنے ہو سکتے ہیں (1) یہ وہ کتاب ہے (2) وہ یہ کتاب ہے
218
Page 227
(3) یہی کامل کتاب ہے (4) وہی کامل کتاب ہے.مذکورہ بالا معانی اس صورت میں ہیں کہ ذلک مبتد ا ہو اور الکتاب خبر لیکن ایک صورت
یہ بھی ہے کہ ذلک کو مبتدا اور الکتاب کو عطف بیان اور لاریب فیہ کو اس کی خبر سمجھا جائے اس
صورت میں اس کے معنی یوں ہوں گے (1) یہ یعنی کامل کتاب اپنے اندر کوئی ریب کی بات
نہیں رکھتی (2) وہ کامل کتاب (یعنی ہدایت انبیاء) اپنے اندر کوئی ریب کی بات نہیں رکھتی.لاريب فِيْهِ کے یہ معنے بھی ہیں کہ قرآن کریم کی صداقت کا ایک مزید ثبوت اور اس کی
ضرورت حقہ کا ایک زبر دست گواہ یہ ہے کہ اس میں کسی قسم کا شک نہیں.جولوگ عربی زبان سے ناواقف ہونے کے باوجود قرآن کریم پر اعتراض کرنے میں
جلدی کرتے ہیں انہوں نے اس جملہ کے صرف یہی معنے کئے ہیں اور پھر اس پر یہ اعتراض کیا
ہے کہ قرآن کریم نے یہ دعویٰ کر کے کہ اس میں کوئی شک نہیں گویا خوداپنے مشکوک ہونے کا
اعتراف کیا ہے کیونکہ جب دل میں چور نہ ہو تو انسان کو یہ خیال ہی نہیں ہو سکتا کہ لوگ مجھ پر
جھوٹا ہونے کا الزام لگائیں گے ( ویری بحوالہ رومن قرآن ) اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ
اس نادان معترض کو یہ بھی معلوم نہیں کہ سورۃ بقرہ رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی وحی نہیں
ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ اپنے دل کے خدشہ کی وجہ سے شک کی نفی کی گئی ہے بلکہ یہ سورۃ تو مدینہ
منورہ میں نازل ہوئی ہے جبکہ قرآن کریم کو نازل ہوتے ہوئے تیرہ سال سے زائد گذر چکے
تھے اور اس عرصہ میں کفار ہزاروں شبہات قرآن کریم کے بارہ میں پیش کر چکے تھے.پس اس
قدر عرصه تک دشمنوں کے اعتراضات لینے کے بعد بھی اگر قرآن کریم کا حق نہیں کہ وہ یہ کہے کہ
اس میں کوئی شک کی بات نہیں تو اس کے یہ معنے ہوں گے کہ جو سچا ہو اسے کبھی یہ نہیں کہنا
چاہیے کہ وہ سچا ہے ورنہ اس کی سچائی میں شک پڑ جائے گا.یہ دعویٰ بالبداہت باطل ہے اور
کبھی کسی عقلمند نے اسے قبول نہیں کیا.نہ کبھی کسی صادق نے اس پر عمل کیا ہے.اور یہ نکتہ
صرف رومن قرآن کے مصنف کے ہی ذہن میں آیا ہے اور یورنڈ ویری ہی ایک ایسے شخص
219
Page 228
ہیں جن کو اس خلاف عقل دعویٰ کی تصدیق کی توفیق ملی ہے.مگر افسوس ہے کہ ان دونوں پادریوں کو خود اپنی مذہبی کتب پر غور سے مطالعہ کرنے کا کبھی
موقعہ نہیں ملا.اگر وہ اپنی مذہبی کتب کا غور سے مطالعہ کرتے تو انہیں معلوم ہوتا کہ وہ یہ
اعتراض قرآن کریم کی صداقت کے خلاف نہیں کر رہے بلکہ خود اپنی کتب کے خلاف کر رہے
ہیں چنانچہ مندرجہ ذیل حوالے جو بہت سے حوالوں میں سے چند ہیں ثابت کرتے ہیں کہ بالکل
اس قسم کے محاورات بائبل میں بھی استعمال ہوئے ہیں.امثال 8 / 8 ”میرے منہ کی ساری
باتیں صداقت سے ہیں ان میں کچھ ٹیڑھا ترچھا نہیں.“ یسعیاہ 19 / 45 ”میں خداوند سیچ
کہتا ہوں اور راستی کی باتیں فرماتا ہوں.مطاؤس (1) طیطس 8, 3 یہ بات سچ ہے.“
مکاشفات 6،21/5 / 22 یہ باتیں سچ اور برحق ہیں.“
ان حوالہ جات سے ظاہر ہے کہ اپنی سچائی پر زور دینے کے لئے عہد نامہ قدیم اور جدید دونوں
نے بالکل قرآن کریم کے مشابہ الفاظ استعمال کئے ہیں.اور اگر اس قسم کے محاوروں کے
استعمال سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قائل اپنی سچائی کی نسبت شبہ رکھتا ہے تو یہ شبہ بہت زیادہ
مصنفین عہد نامہ قدیم اور جدید کے دل میں پایا جاتا تھا.مگرحق یہ ہے کہ یہ اعتراض نہ بائبل پر
پڑتا ہے نہ قرآن کریم پر.کیونکہ جب شبہات پیش کئے جائیں تو اپنے دعوی کی سچائی پر زور
دینے کے لئے ایسے کلمات کا استعمال شک پر نہیں بلکہ یقین پر دلالت کرتا ہے.اور قرآن کریم
میں یہ الفاظ ابتدائی سورتوں میں استعمال نہیں کئے گئے بلکہ ایک لمبے عرصہ کی مخالفت کے بعد
استعمال کئے گئے ہیں.ریب اس شک کو نہیں کہتے جو تحقیق کے راستہ میں محمد ہوتا ہے اور جس پر علمی ترقی کا مدار
ہے.بلکہ ریب اُس شک کو کہتے ہیں جو بلا وجہ اور بدظنی پر مبنی ہو اور ان معنوں کی رُو سے اس میں
کوئی ریب نہیں“ کے یہ معنے ہوئے کہ قرآن کریم میں کوئی ایسی بات نہیں جو بدظنی اور صداقت
کے انکار پر مشتمل ہو.یعنی اس میں جس قدر امور ہیں وہ تحقیقی ہیں.ظنی نہیں.اور یہ امر ظاہر ہے کہ
220
Page 229
قرآن کریم کا یہ دعوی کہ اس میں جس قدر امور میں تحقیقی ہیں ظنی نہیں کوئی معمولی دعوی نہیں.پس لاریب فیہ کہہ کر قرآن کریم نے اس امر کو پیش کیا ہے کہ گو قرآن کریم
ایک کامل کتاب ہے یعنی ہر ضروری امر کے متعلق اس میں بحث کی گئی ہے پھر بھی وہ ظنی اور شکی
امور کو پیش نہیں کرتا بلکہ ہر امر کی دلیل ساتھ دیتا ہے اور تحقیق کے ساتھ ہر مسئلہ کو پیش کرتا ہے
اور یہ امر قرآن کریم کی افضلیت کا ایک زبر دست ثبوت ہے.کیونکہ یہ امر تو آسان ہے کہ
ایک دو امور جو تحقیقی طور پر ثابت ہو چکے ہوں ان کو با دلائل بیان کر دیا جائے لیکن یہ امر نہایت
مشکل ہے کہ ہر ضروری امر کے متعلق بحث بھی کی جائے اور پھر ہر بات کو دلائل کے ساتھ
ثابت بھی کیا جائے اور ظن اور گمان کی حد سے نکال کر یقین اور وثوق کے مقام پر کھڑا کر دیا
جائے.ظاہر ہے کہ جو کتاب اپنے تمام دعاوی کو اس طرح پیش کرے گی اس کے سچا ہونے
میں کسی منصف مزاج کوشک اور ترڈ د نہ ہو سکے گا.لا ريب فيه کے ایک معنے یہ بھی ہیں کہ قرآن کریم کے محفوظ ہونے میں کوئی شک
نہیں اور ذلك الكتب کے بعد یہ الفاظ اس مضمون پر دلالت کرتے ہیں کہ اس کتاب کے
بعد کوئی اور کتاب نازل نہ ہوگی اور یہ دنیا کے لئے آخری ہدایت نامہ ہے.کیونکہ جیسا کہ بتایا
جا چکا ہے ذلك الكتب کا ایک مفہوم یہ ہے کہ یہ کامل کتاب ہے اور تمام انسانی ضروریات
کے پورا کرنے کا سامان اس میں موجود ہے.اس قسم کی کتاب کے بعد دوسری کتاب اسی
صورت میں نازل ہوسکتی ہے جب وہ محفوظ نہ رہے.کیونکہ نئے قانون کی دو ہی صورت میں
ضرورت ہوتی ہے یا تو اس وقت جبکہ پہلا قانون ناقص ہو اور کسی وقت جا کر لوگوں کی ضروریات
کے پورا کرنے سے قاصر ہو جائے یا پھر اس صورت میں کہ پہلا قانون دنیا سے کلی طور پر یا
جزوی طور پر مفقود ہو جائے اور اسے دوبارہ تازہ کرنے کی ضرورت ہو.سوذلك الكتب کے
بعد لاريب فيه فرما کر یہ بتایا کہ یہ کامل کتاب ہمیشہ زمانہ کی دست برد سے محفوظ رہے گی اور
کوئی زمانہ ایسا نہ آئے گا کہ اس کے بارہ میں یہ شک کیا جا سکے کہ آیا اس کے الفاظ وہی ہیں
جو کسی وقت میں خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتے تھے یا ان میں کوئی تغیر تبدل ہو گیا ہے؟
221
Page 230
اور چونکہ ایسا زمانہ اس پر کوئی نہ آئے گا یہ کتاب منسوخ نہ ہوگی اور آئندہ سب زمانوں میں اسی
کے مطابق لوگوں کو روحانی زندگی بسر کرنی پڑے گی.یہ مفہوم بھی قرآن کریم کی ایک زبر دست
خوبی پر دلالت کرتا ہے اور آج بھی جبکہ قرآن کریم کے نزول پر تیرہ سو سال سے زائد عرصہ گزر
چکا ہے دوست تو الگ رہے دشمن بھی اس کے محفوظ ہونے کی شہادت دیتے ہیں.خلاصہ کلام یہ کہ لاریب فیہ میں صرف اس امر کی تاکید نہیں کی گئی کہ یہ کلام سچا ہے اور اس
میں کوئی شک نہیں.بلکہ ریب کے معنوں پر نظر کرتے ہوئے اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ
(1) اس میں کسی صداقت کا انکار نہیں ہے بلکہ سب صداقتوں کا اقرار کیا گیا ہے اور
مذہب کے سب ضروری امور پر سے تہمتوں اور بدگمانیوں کو دور کیا گیا ہے
(2) اس میں کوئی ظنی اور شکی بات نہیں بلکہ ہر بات دلیل سے بیان کی گئی ہے
(3) یہ کلام محفوظ اور یقینی ہے اور ہمیشہ محفوظ رہے گا
(4) اس میں کوئی ایسا امر نہیں جو انسان کے لئے تکلیف اور تباہی کا موجب ہو
(5) اس میں سب ضروری امور بیان کر دیئے گئے ہیں اور کوئی ایسا مذہبی ، اخلاقی ، تمدنی ،
اقتصادی، سیاسی وغیرہ مسئلہ نہیں جس کے بارہ میں اس میں مکمل تعلیم نہ دی گئی ہو.ا هُدًى لِلْمُتَّقِينَ.ان الفاظ میں یہ بتایا کہ
(1) قرآن کریم میں وصال الہی کی تڑپ پیدا کرنے کے سامان موجود ہیں.یعنی ہر
فطرت صحیحہ کو اس کی تلاوت کے ذریعہ سے وہ ضروری دھکا لگتا ہے جس کے بغیر والہانہ اور
عاشقانہ قدم ارواح اپنے معشوق حقیقی کی طرف نہیں اٹھا سکتیں.صرف فلسفیانہ خیالات کا پیدا
ہونا انسان کے لئے کافی نہیں ہوتا کیونکہ فلسفہ صرف خیالات کو درست کرتا ہے.ایک نا قابل
برداشت جذبہ اس سے پیدا نہیں ہوتا.مگر عمل کی تکمیل کے لیے ضروری ہے کہ فطرۃ انسانی کو
ایک ایسا دھکا لگے کہ وہ آپ ہی آپ آگے بڑھتی چلی جائے.خدمت اور ایثار پر فلسفی
زبردست تقریر کر سکتا ہے.ایک جاہل ماں اس کا لاکھواں حصہ بھی بیان نہیں کر سکتی لیکن اپ
بچہ کے لئے جس ایثار اور قربانی کا عملی نمونہ وہ دکھاتی ہے ایک فلسفی بنی نوع انسان کے لئے اس
اپنے
222
Page 231
نمونہ کا لاکھواں حصہ بھی پیش نہیں کر سکتا.پس جب تک کوئی کتاب هُدًى لِلْمُتَّقِينَ نہ ہو
یعنی جن لوگوں کے خیالات و افکار دلیل اور بُرہان سے پاک ہو چکے ہوں اُن کے اندر عشق اور
محبت کی آگ نہ بھڑکا دے اور ایک طرف خدا تعالیٰ کی طرف محبت سے بڑھتے چلے جانے اور
دوسری طرف مخلوق کی طرف شفقت سے جھکتے چلے جانے کا بے پناہ جذ بہ نہ پیدا کر دے وہ دنیا
کی عملی اصلاح میں کامیاب نہیں ہو سکتی.اور قرآن کریم هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ کے الفاظ سے اسی
مقصد کے پورا کرنے کا دعویٰ کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس کتاب کے مطالعہ سے انسانی فطرت
کو وہ ابتدائی دھکا لگتا ہے جو اُ سے عشق کی راہ پر گامزن کر دیتا ہے.دوسرے معنے ہدایت کے اس ارشاد کے ہوتے ہیں جو نبیوں کے ذریعہ سے انسانوں کو
پہنچایا جاتا ہے.ان معنوں کے رُو سے اس جملہ کے معنے یہ ہوں گے کہ جولوگ اس امر کے
شائق ہیں کہ ان کو ان کے خالق و مالک کی طرف سے ہدایت ملتی رہے ان کی خواہش کے پورا
کرنے کے بھی اس میں سامان موجود ہیں اور خواہ کسی درجہ کا متقی ہو اس کی راہنمائی کے لیے
اس کتاب میں پاک اور مصطفیٰ الہی تعلیم موجود ہے جس سے متقی کے دل کو یہ تسکین حاصل ہوتی
ہے کہ وہ صرف اپنی عقل سے کام نہیں لے رہا بلکہ اُسے خدا تعالی کی بتائی ہوئی ہدایت حاصل
ہے جس کی مدد سے وہ ہر قدم یقین اور اطمینان سے اٹھا سکتا ہے اور شک وشبہ کی زندگی.پاک ہو جاتا ہے.تیسرے معنے ہدایت کے عمل کی مزید توفیق اور فکر کی بلندی کے ہیں.ان معنوں کے رو سے
اس جملہ کے یہ معنے ہیں کہ قرآن کریم میں ایسی قوت ہے کہ جب اس کے کسی حکم پر انسان عمل
کرے تو اسے مزید نیکیوں کی توفیق ملتی ہے اور اس کے خیالات میں چلا پیدا ہوتی ہے اور اس کا
فکر اور اس کا حوصلہ بڑھتا چلا جاتا ہے اور باریک در بار یک تقوی کی راہیں اس پر کھولی جاتی
ہیں.گویا وہ ایک لامتناہی نیکی اور تقویٰ کی نہ ختم ہونے والی راہوں پر چل پڑتا ہے اور اس کی
ترقیات کی کوئی انتہا مقرر نہیں کی جاسکتی.دوسری جگہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَأَشْهُمْ تَقُوهُمُ (محمد (18) یعنی جو لوگ ہدایت پا جائیں
223
Page 232
انہیں اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے ذریعہ سے ہدایت میں اور بھی بڑھاتا ہے اور ان کے
مناسب حال تقویٰ انہیں عطا کرتا ہے.اس آیت سے ظاہر ہے کہ ہدایت اور تقویٰ کسی ایک
مقام کا نام نہیں ہیں بلکہ ہدایت کے بھی مختلف مقامات ہیں اور تقویٰ کے بھی مختلف مقامات
ہیں.قرآن کریم ہدایت یافتوں کو ان کے مقام سے اوپر کے مقام ہدایت کی طرف راہنمائی
کرتا ہے اور پھر اس مقام کے مناسب حال تقویٰ کا مقام اس شخص کو دیا جاتا ہے اور یہ سلسلہ
لامتناہی ترقیات کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے.اسی طرح فرماتا ہے وَالَّذِيْنَ جَاهَدُ وَافِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا (العنكبوت 70) یعنی
جولوگ ہماری محبت اور ہمارے وصال کے حصول کے لئے ہمارے بتائے ہوئے قواعد کے
مطابق ( اس پر فینا کے الفاظ دلالت کرتے ہیں اور ان سے ایک مراد قرآن کریم ہے )
جد و جہد کرتے ہیں انہیں ہم یکے بعد دیگرے ان راستوں کا پتہ بتاتے چلے جاتے ہیں جو ہم تک
پہنچنے والے ہیں.اس آیت میں بھی اسی طرف اشارہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف ہدایت کے
راستے محدود نہیں بلکہ ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا راستہ ہے.اسی طرح فرماتا ہے نُورُ هُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَثْهِمْ لَنَا
نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير (التحريم (9) یہ آیت ما بعد الموت زندگی کے متعلق
ہے اور اس میں بتایا گیا ہے کہ قیامت کو جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مومن جنت کی
طرف جائیں گے تو ان کے ایمان و عمل کے نتیجہ میں پیدا شدہ نور ان کے آگے ہوگا اور وہ یہ کہتے
جائیں گے کہ اے ہمارے رب ہمارے نور کو مکمل کر دے اور ہماری کمزوریوں کو ڈھانپ
دے.تو ہر شے پر قادر ہے.اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہدایت صرف اسی دنیا میں نہیں
بڑھتی بلکہ بعد الموت بھی ہدایت اور عرفان میں انسان ترقی کرے گا اور نئی طاقتیں اُسے ملتی جائیں
گی.خلاصہ یہ کہ ہدایت کے لفظ میں اس امر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور دوسری آیات
قرآنیہ اس کی مؤید ہیں کہ روحانی ترقیات غیر محدود ہیں اور قرآن کریم متقیوں کو ان اعلی ترقیات
کی طرف بڑھا تا لئے جاتا ہے.224
Page 233
چوتھے معنے ہدایت کے قرآن کریم سے یہ ثابت ہیں کہ انجام بخیر اور جنت حاصل ہو جاتی
ہے.ان معنوں کے رُو سے اس جملہ کے معنے ہوتے ہیں کہ قرآن کریم میں ایسی تعلیم ہے کہ
جس کی امداد سے خدا ترس انسان اپنے منزل مقصود یعنی جنت کو حاصل کر لیتا ہے.یاد رکھنا
چاہئے کہ یہ دعویٰ سب مذاہب ہی کرتے ہیں اور بظاہر اس مضمون میں کوئی جدت یا افضلیت
نہیں پائی جاتی.لیکن جب ہم قرآن کریم کو دیکھتے ہیں کہ اس میں جنت کے حصول کے کیا معنے
ہیں تو پھر یہ دعویٰ بالکل جدید اور نرالا ہو جاتا ہے کیونکہ قرآن کریم میں لکھا ہے کہ جنت کے
حصول کے یہ معنے نہیں کہ انسان مرنے کے بعد جنت میں داخل ہو جائے بلکہ مرنے کے بعد
کی جنت کا حصول اس دنیا میں جنت کے حصول سے وابستہ ہے.جسے اس دنیا میں جنت مل
جائے صرف اسی کو بعد الموت جنت ملے گی.چنانچہ فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ
جَنَّتَانِ (الرحمن 47) یعنی جو شخص تقویٰ کے بچے مقام پر ہوتا ہے اسے دو جنتیں ملتی ہیں.ایک
اس دنیا میں اور ایک اگلے جہان میں.اور ایک دوسری جگہ فرماتا ہے مَنْ كَانَ في هذه آغمی
فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ آنمی (بنی اسرائیل (73) یعنی جو شخص اس دنیا میں اندھا ہو یعنی اسے دیدار الہی
نصیب نہ ہو وہ اگلے جہان میں بھی اندھا ہی ہوگا اور دیدار الہی یا دوسرے الفاظ میں جنت سے
محروم رہے گا.قرآن کریم کی اس تشریح کو مدنظر رکھتے ہوئے جنت کے ملنے کے معنے صرف یہ نہیں کہ
مرنے کے بعد قرآن کریم کا مومن جنت حاصل کرے گا کیونکہ یہ صرف ایک دعوی ہے جس کی
کوئی دلیل نہیں.بلکہ اس کے یہ معنے ہیں کہ قرآن کریم پر ایمان لانے والا اور اس کی روشنی
سے فائدہ اٹھانے والا شخص اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہو جاتا ہے اور ایمان
بالغیب اس کے لئے ایمان بالمعاینہ ہو جاتا ہے.وہ صرف عقیدۃ اس امر کو نہیں مانتا کہ اسے
مرنے کے بعد جنت مل جائے گی بلکہ اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ اپنی صفات کو اس کے لئے ظاہر
کرتا ہے اور اپنے وجود کو اس کے سامنے لے آتا ہے یہاں تک کہ وہ موت سے پہلے ہی اپنے
آپ کو جنت میں محسوس کرنے لگتا ہے اور جسمانی موت صرف اُس کے مشاہدہ کو زیادہ روشن
225
Page 234
کرنے کا موجب ہوتی ہے ورنہ مشاہدہ اور دیدار الہی اُسے اسی دنیا میں میسر آ جاتا ہے.ظاہر ہے کہ یہ ایسا مقام ہے جس کے بعد کوئی بے چینی اور شک باقی نہیں رہتا اور ایسا انسان ہر
ٹھوکر اور ابتلاء سے محفوظ ہو جاتا ہے اور گویا اسی دنیا میں خدا تعالیٰ کی گود میں جا بیٹھتا ہے.پس قرآن
کا مومنوں کو قرآن کریم کے ذریعہ سے جنت ملنے کا دعوی کرنا محض ایک بے دلیل دعوی نہیں بلکہ وہ
اسے ایک ایسی شہادت کے طور پر پیش کرتا ہے جس کا جھوٹ اور سچ اسی دنیا میں آزمایا جا سکتا
ہے.اور اسلام کی تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں ہر زمانہ میں ایسے لوگ پیدا ہوتے رہے
ہیں جو اس دعوی کے لئے دلیل کے طور پر تھے اور جن کو اللہ تعالیٰ کا وصال اور دیدار کامل طور پر اسی
دنیا میں حاصل ہو گیا اور اسی دنیا میں جنت میں داخل ہو گئے.یعنی ہر قسم کے شیطانی حملوں سے محفوظ ہو
گئے اور ہر قسم کی روحانی نعمتوں سے متمتع ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے تازہ بتازہ کلام کو انہوں نے سُنا اور
اس سے بالمشافہ انہوں نے باتیں کیں اور اس کے زندہ نشانوں کو انہوں نے اپنی ذات میں دیکھا اور
دوسروں کے وجودوں میں انہیں دکھایا.بعض لوگ اس آیت پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر قرآن کریم متقیوں کے لئے
ہدایت ہے تو معلوم ہوا کہ متقی پیدا کرنے کے لئے اور کسی کلام یا کتاب کی ضرورت ہے.سو
یادر ہے کہ یہ اعتراض محض قلت تدبر سے پیدا ہوا ہے کیونکہ قرآن کریم تقویٰ پیدا کرنے کا بھی
مدعی ہے.چنانچہ فرماتا ہے فَأَنْزَلَ اللهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْزَمَهُمْ
كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقِّ بِهَا وَأَهْلَهَا (الفتح (27) یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور اپنی
کتاب پر ایمان لانے والوں پر سکینت اور اطمینان نازل کیا اور اُن سے تقویٰ کی حقیقت کو
وابستہ کر دیا اور مومن بالقرآن ہی حقیقت تقویٰ کے مستحق اور اس کے اہل ہیں.اس آیت سے
صاف ظاہر ہے کہ قرآن کریم کے ذریعہ سے اور اس پر ایمان لا کر انسان کو کامل تقویٰ میسر آ تا
ہے بلکہ ایسا تقویٰ میسر آتا ہے جو دائمی ہوتا ہے.بلکہ اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ تقویٰ
کے اہل اور اس کے ساتھ حقیقی تعلق رکھنے والے صرف مومنین قرآن ہیں.226
Page 235
اس آیت کی موجودگی میں یہ اعتراض کرنا کہ گویا قرآن کریم صرف متقیوں کو ہدایت دینے کا
دعویدار ہے، تقویٰ پیدا کرنے کا دعویٰ نہیں کرتا بالبداہت باطل ہے.اس کے برخلاف قرآن کریم
تو اس امر کا مدعی ہے کہ حقیقی تقویٰ صرف قرآن کریم پر ایمان لانے سے پیدا ہوسکتا ہے.اس آیت کے علاوہ قرآن کریم کی اور بہت سی آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کریم
صرف متقیوں کے لیے ہدایت نہیں بلکہ سب بنی نوع انسان کے لئے ہدایت ہے خواہ وہ روحانی
زندگی میں اعلیٰ مقام پر ہوں یا ادنی پر.چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هَذَا بَيَانُ لِلنَّاسِ وَهُدًى
(آل عمران 139) یہ قرآن تمام انسانوں کے لئے ضروری امور بیان کرتا ہے اور انہیں ہدایت
دیتا ہے.یہ آیت بتاتی ہے کہ قرآنی ہدایت صرف متقیوں کے لئے نہیں بلکہ تمام انسانوں
کے لئے ہے.اسی طرح ایک اور جگہ قرآن کریم میں ہے هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنت من
الهدى (البقرة (186) یعنی قرآن کریم سب انسانوں کے لئے ہدایت ہے اور اس میں
ہدایت کی تمام اقسام بیان کی گئی ہیں.اسی طرح فرماتا ہے.وَلَقَدْ صَرَفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَل (الکھف (55) یعنی اس قرآن میں تمام
انسانوں کے فائدہ کے لئے خواہ متقی ہوں یا غیر متقی ہر بات اعلی سے اعلی پیرا یہ میں بیان کر دی گئی ہے
یعنی ہر انسان کی حالت کے مطابق اس میں ایسی تعلیم ہے جو اسے اوپر کے درجہ کی طرف لے جاتی
ہے اور اس کی روحانی ضرورتوں کو پورا کرتی ہے.اسی طرح فرماتا ہے وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي
هَذَا الْقُرْآن مِنْ كُلِّ مَثل (الروم (59) اس آیت کے بھی قریب وہی معنے ہیں جو اوپر کی آیت کے
ہیں صرف فرق یہ ہے کہ پہلی آیت میں صد فنا کہا گیا تھا یہاں ضربنا کہا گیا ہے.اور صرفنا
میں اس امر پر زور ہے کہ مختلف پیرایوں سے اس ہدایت کو بیان کیا ہے.اور ضربنا میں اس امر
پر زور ہے کہ فطرت
کی صحیح مثالوں اور واضح نمونوں کے مقابل پر رکھ رکھ کر ہدایت کو بیان کیا گیا
ہے.اسی طرح فرماتا ہے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا (بنی اسرائیل (42) یعنی
قرآن کریم میں تمام ضروری امور ہدایت مختلف پیرایوں میں بیان کئے گئے ہیں تا کہ لوگ نصیحت
227
Page 236
حاصل کریں اور فائدہ اٹھائیں.اس جگہ بھی متقیوں یا مومنوں کے لئے ہدایت کو مخصوص نہیں کیا گیا
بلکہ تمام انسانوں کے لئے اسے پیش کیا گیا.قرآن کریم کی متعدد آیات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ تقویٰ کی راہیں بھی قرآن کریم
نے تمام انسانوں کے لئے بیان کی ہیں.چنانچہ فرماتا ہے يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ
الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (البقرہ22) یعنی اے انسانو ( نہ کہ
مومنو یا مسلمانو) اپنے اس رب کی جس نے تم کو اور تمہارے باپ دادوں کو پیدا کیا ہے عبادت
کرو تا کہ تم متقی بنو.اسی طرح فرماتا ہے.وَكَذلِكَ اَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَ فُنَا فِيْهِ مِنَ
الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُون (طه 114) یعنی قرآن کریم کو ہم نے عربی زبان میں اتارا ہے اور اس
میں تمام عذاب کی خبریں بھی بیان کی گئی ہیں تا کہ جو مومن نہیں وہ بھی متقی ہو جائیں.اس آیت
سے صاف ظاہر ہے کہ قرآن کریم کا فروں کو بھی متقی بناتا ہے.اب رہا یہ سوال کہ پھر اس جگہ یہ کیوں فرمایا کہ قرآن کریم متقیوں کے لئے ہدایت ہے
یہ کیوں نہ فرمایا کہ قرآن کریم تقویٰ پیدا کرتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس جگہ قرآن کریم
کی افضلیت کا ذکر ہے یعنی یہ بیان ہے کہ دوسری کتب کی موجودگی میں اس کتاب کی کیا
ضرورت ہے.پس اس مضمون کے لحاظ سے ان اعلیٰ مقامات کے حصول کا ذکر ہی مناسب اور
درست تھا جن میں قرآن کریم منفرد ہے اور جس میں اس کا مقابلہ کرنے کا دوسرے مذاہب کو
دعوی تک بھی نہیں.م اس جواب کے علاوہ اس اعتراض کا ایک اور بھی جواب ہے اور وہ یہ کہ قرآن کریم میں
تقویٰ کی ایک اور بھی تعریف بیان کی گئی ہے اور اس تعریف کے رُو سے تقویٰ کا تعلق انسانی
فطرت سے ہے نہ کہ مذہب سے.چنانچہ سورہ شمس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا
وَتَقُوهَا - ہر انسان کو اس کی پیدائش کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک امتیازی قابلیت بخشی ہے
جس کے ذریعہ سے وہ بڑے اور بھلے میں تمیز کرتا ہے.یہ قابلیت مسلمان یا غیر مسلمان کے
228
Page 237
ساتھ تعلق نہیں رکھتی بلکہ ہر انسان میں پیدا کی گئی ہے.پس اس تعریف کے مطابق تقویٰ کے
معنے فطرت کی حفاظت کے ہیں.نہ کہ کسی خاص مذہب یا عقیدہ کے.اور یہ ظاہر ہے کہ
ہدایت وہی لوگ پاسکتے ہیں جو فطرت کو گندے اثرات سے پاک رکھتے ہیں ورنہ جولوگ
فطرت کو پاک رکھنے کی کوشش نہیں کرتے اور صداقت کے ماننے سے انکار کرتے ہیں وہ
ہدایت نہیں پاسکتے.ان کو ہدایت تبھی مل سکتی ہے جب جبر سے کام لیا جائے اور قرآن کریم جبر
کے خلاف ہے.خلاصہ یہ کہ اوپر کی تعریف کے رُو سے اس آیت کے یہ معنے ہوتے ہیں کہ جولوگ
صداقت کو قبول کرنے کے لئے تیار ہوں قرآن کریم ان کو ہدایت دیتا ہے اور اعلیٰ مدارج
تک پہنچاتا ہے.اور جولوگ ہدایت کو ماننے کے لئے تیار ہی نہ ہوں وہ گو یا اپنی ہلاکت کا خود
ہی فیصلہ کر دیتے ہیں اور انہیں ہدایت جبر ہی سے دی جاسکتی ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ
جبر سے جو ہدایت ملے اس کا فائدہ جبر کرنے والے کو حاصل ہوسکتا ہے، اسے نہیں ہو سکتا جسے
ہدایت دی جائے.جیسے مثلاً کسی سے زبر دستی مال چھین کر صدقہ کر دیا جائے تو اس صدقہ کا
کوئی فائدہ اُسے نہیں مل سکتا جو صدقہ کا قائل ہی نہیں اور صدقہ دینا ہی نہیں چاہتا.خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس آیت میں دوسری کتب کی موجودگی میں قرآن کریم کی ضرورت کو
بیان کیا گیا ہے اور بتایا ہے کہ غیر الہامی کتب کی موجودگی میں تو اس کی یہ ضرورت ہے کہ بغیر
آسمانی ہدایت کے انسان ہدایت پاہی نہیں سکتا.اس لئے آسمانی ہدایت کی ضرورت تھی جسے
قرآن کریم نے پورا کیا ہے اور الہامی کتب کی موجودگی میں اس کی یہ ضرورت ہے کہ (1) اس
سے پہلے سب ہدایت نامے نامکمل تھے.یہ کمل ہے (2) ان میں خرابیاں پیدا ہوگئی ہیں اور یہ
سب خرابیوں سے محفوظ ہے ( 3 ) وہ سب ہدایت نامے ایک ایک قوم اور مذہب کے لئے
تھے اور یہ ہدایت نامہ سب قوموں کے لئے ہے اور سب قوموں کے بزرگوں کی عزت قائم
کرنے اور سب ضائع شدہ ہدایتوں کو زندہ کرنے کے لئے آیا ہے.(4) ان کتب میں بوجہ
229
Page 238
اندرونی بیرونی نقائص کے وصال الہی پیدا کرنے کی خاصیت باقی نہ رہی تھی اب اس کے ذریعہ
سے پھر انسان کو وصال الہی حاصل کرنے اور کلام الہی سے مشرف ہونے کا موقعہ دیا جائے گا
وغیر بادغیر ہا.يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ میں غیب سے مراد ہر وہ چیز ہے جو حواس ظاہری سے معلوم نہ کی جا
سکے اور سرسری نظر میں انسانی عقلیں اس تک نہ پہنچ سکیں ( مفردات )
لسان میں ہے وَقَوْلُهُ تعالى يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ أَن يُؤْمِنُونَ بِمَا غَابَ عَنْهُمْ لَه يُؤْمِنُوْنَ
بِالْغَيْیب میں غیب کے یہ معنے ہیں کہ جو باتیں ان کی آنکھوں سے پوشیدہ ہیں اُن پر ایمان
لاتے ہیں.وَالْغَيْبُ مَا غَابَ عَنِ الْعُيُونِ وَإِنْ كَانَ مُحَضَّلَّا فِي الْقُلُوبِ أَوْ غَيْرَ مُحَضّل اور
غیب کا لفظ ہر اس امر پر بولا جاتا ہے جو آنکھوں سے پوشیدہ ہو خواہ وہ ایسا امر ہو کہ دماغی طور پر
اس کا علم حاصل ہو یا ایسا ہو کہ عقلاً بھی اس کا علم حاصل ہو كُلُّ مَكَانٍ لَا يُدْرَى مَا فِيهِ فَهُوَ
غيب.ہر وہ جگہ جس کے متعلق معلوم نہ ہو کہ اس کے اندر کیا ہے اس کو غیب کہتے ہیں.وَكَذلِكَ الْمَوْضِعُ الَّذِى لا يدرى مَا وَرَاءَهُ.اور اسی طرح اُس جگہ پر بھی غیب کا لفظ بولتے
ہیں جس کے پیچھے کی اشیاء کا علم نہ ہو.نیز کہتے ہیں.غابَ الرَّجُلُ غَيْبًا أَى سَافَرَ أَوْ بَان - که
فلاں شخص نے سفر کیا یا کسی سے جدا ہو گیا.پس غیب ہر وہ امر ہے جو آنکھوں سے پوشیدہ ہو، نہ یہ کہ وہ موہوم اور بے ثبوت ہو.پس.يُؤْمِنُونَ بِالْغَیب کے معنے ہوں گے (1) ہر وہ چیز (امر) جو ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں
آتی اور ظاہری حواس اُسے پانے سے قاصر ہیں لیکن وہ موجود ہے اور ایمانیات میں داخل ہے
اس کے حق ہونے پر پختہ یقین رکھتے ہیں اور اس کا اعتراف کرتے ہیں اور اس کی تصدیق
کرتے ہیں.(2) اس زندگی کے بعد کے پیش آنے والے حالات پر پختہ یقین رکھتے ہیں
(3) نیز اس کے یہ بھی معنے ہو سکتے ہیں کہ وہ غیبوبت کی حالت میں یعنی علیحدگی میں بھی ایمان
رکھتے ہیں اور ان میں منافقوں کی طرح دورنگی نہیں پائی جاتی.230
Page 239
أقام الصلوة کے معنے ہیں آدام فعلها نماز پر دوام اختیار کیا.آقام للصلوۃ کے
معنے ہیں نادی تھا نماز کے لئے تکبیر کہی.آقامَ اللهُ السُّوقَ : جَعَلَهَا نَافِقَةٌ الله تعالیٰ نے
برکت دی اور بازار کو بارونق بنا دیا (اقرب) مفردات میں ہے يُقِيمُونَ الصَّلوة آئی
يُدِيمُونَ فِعْلَهَا وَيُحَافِظُونَ عَلَيْهَا.نماز کو اس کی شرائط کے مطابق ادا کرتے ہیں اور اس پر
دوام اختیار کرتے ہیں.نیز لکھا ہے انّما خُضَ لفظ الْإِقَامَةِ تَنْبِيْهَا أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ
فِعْلِهَا تَوْفِيَةُ حُقُوقِهَا وَشَرَائِطِهَا.کہ صلوۃ کے ذکر کے ساتھ اقامت کا لفظ اس لئے لایا گیا
ہے تا کہ اس طرف توجہ مبذول کرائی جائے کہ نماز کے حقوق اور شرائط کو پوری طرح ادا کیا
جائے نہ کہ صرف ظاہری صورت میں اس کو ادا کر دیا جائے.لسان میں الْقِیام کے معنے
العزم کے بھی لکھے ہیں یعنی کسی چیز کا پختہ ارادہ کر لینا.الصلوة کے اصطلاحی معنے عِبَادَةٌ فِيْهَا رُكُوعٌ وَسُجُود کے ہیں.یعنی اس مخصوص طریق
سے دعا کرنا جس میں رکوع و سجود ہوتے ہیں، جس کو ہماری زبان میں نماز کہتے ہیں.اس کے
علاوہ اس کے اور بھی کئی معانی ہیں جو بے تعلق نہیں بلکہ سب ایک ہی حقیقت کی طرف
راہنمائی کرتے ہیں.چنانچہ اس کے دوسرے معنے مندرجہ ذیل ہیں الرحمة رحمت.الدين.شریعت الإِسْتِغْفَارُ بخشش مانگنا - الدُّعَاءُ دعا (اقرب) التَّعْظِيمُ.بڑائی کا
اظہار - البركة برکت (تاج) وَالصَّلوةُ مِنَ اللهِ الرَّحْمَةُ وَمِنَ الْمَلَائِكَةِ الْإِسْتِغْفَارُ
وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ الدُّعَاءُ وَمِنَ الطَّيْرِ وَالْهَوَاةِ التَّسْبِيحُ.اور صلوۃ کا لفظ جب اللہ تعالیٰ کے
لئے بولا جائے تو اس کے معنے رحم کرنے کے ہوتے ہیں.اور جب ملائکہ کے لئے استعمال ہو تو
اس وقت اس کے معنے استغفار کے ہوتے ہیں اور جب مومنوں کے لئے بولا جائے تو اس کے
معنے دعا یا نماز کے ہوتے ہیں اور جب پرند اور حشرات کے لئے یہ لفظ استعمال ہو تو اس کے
معنے تسبیح کرنے کے ہوتے ہیں.وَهِيَ لَا تَكُونُ إِلَّا فِي الْخَيْرِ بِخِلَافِ الدُّعَاءِ فَإِنَّهُ يَكُونُ فِي
الخير والشر - اور لفظ صلوۃ صرف نیک دُعا کے لئے استعمال ہوتا ہے لیکن لفظ دعا ، بددعا اور نیک
231
Page 240
دعا دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے.لفظ صلوۃ کے ایک معنے حُسنُ الثَّنَاءِ مِنَ اللهِ عَلَى
الرَّسُولِ کے بھی ہیں یعنی جب صلّی فعل کا فاعل اللہ تعالیٰ ہو اور مفعول آنحضرت صلے اللہ
علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہو تو اس وقت اس کے معنے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول کریم کی
بہترین تعریف کے ہوتے ہیں.(اقرب) وَيُسَى مَوْضِعُ الْعِبَادِةِ الصَّلوۃ اور عبادتگاہ کو
بھی الصلوة کہہ دیتے ہیں (مفردات)
پس يُقِيمُونَ الصَّلوة کے معنے ہوں گے (1) نماز کو باجماعت ادا کرتے ہیں(2) نماز
کو اس کی شرائط کے مطابق اور اس کے اوقات میں صحیح طور پر ادا کرتے ہیں (3) لوگوں کو
نماز کی تلقین کر کے مساجد کو بارونق بناتے ہیں (4) نماز کی محبت اور خواہش لوگوں کے دلوں
میں پیدا کرتے ہیں (5) نماز پر دوام اختیا کرتے ہیں اور اس پر پابندی اختیار کرتے ہیں
(6) نماز کو قائم رکھتے ہیں یعنی گرنے سے بچاتے رہتے اور اس کی حفاظت میں لگے رہتے ہیں.رَزَقْنَا : - رزقی سے متکلم مع الغیر کا صیغہ ہے اور الرزُقُی ( جو رزق کا مصدر ہے ) کے
معنے ہیں العطاء عطا کرنا، دینا.جیسے کہتے ہیں رُزقت علما کہ مجھے علم دیا گیا ہے.اور اس
کے ایک معنی حصہ کے بھی ہیں.جیسے وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِبُونَ (الواقعه : 83)
کہ تم نے اپنے ذمہ یہ کام لگا لیا ہے کہ رسول اور خدا کی باتوں کا انکار کرتے ہو ( مفردات)
اقرب الموارد میں ہے.الرِّزْقُ مَا يُنْتَفَعُ بِهِ.ہر وہ چیز جس سے نفع اٹھایا جائے.اور
رَزَقَهُ اللهُ (يَرْزُقُ) رِزْقًا کے معنے ہیں اوصَلَ إِلَيْهِ رِزْقًا کہ اللہ تعالیٰ نے اُسے ایسی اشیاء عطا
فرمائیں جن سے فائدہ اٹھایا جاسکے.رزق اس چیز کو بھی کہتے ہیں جو غذا کے طور پر استعمال کی
جائے (مفردات).يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ کے یہ معنے ہر گز نہیں کہ متقی وہ ہیں جو بغیر دلیل کے قرآن کریم کی
باتوں کو مان لیتے ہیں کیونکہ یہ معنے قرآن کریم کی دوسری آیات کے خلاف ہیں.ریورنڈ ویری نے اپنی تفسیر میں اس آیت کے نیچے لکھا ہے کہ جب مسلمان اپنی کتاب
232
Page 241
کے اسرار کو مانتے ہیں تو کیوں پہلی کتابوں کے اسرار کو جیسے کہ تثلیث یا کفارہ ہیں، نہیں
مانتے.مگر جیسا کہ ظاہر ہے یہ اعتراض يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ کے معنوں کے نہ سمجھنے کی وجہ سے
ہے.قرآن کریم کسی ایسے امر کو ماننے کی تلقین نہیں کرتا جو بے دلیل ہو بلکہ وہ تو ان دوسرے
مذاہب پر جو بے دلیل باتیں مانتے ہیں اعتراض کرتا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور
اُن کے متبعین کی نسبت گواہی دیتا ہے کہ وہ ہر امر کو دلیل اور برہان سے مانتے ہیں.حقیقت
یہ ہے کہ مسلمان کفارہ اور تثلیث کا اس لئے انکار نہیں کرتے کہ وہ اسرار میں سے ہیں بلکہ اس
لئے کہ یہ مسائل بے دلیل بلکہ خلاف عقل ہیں.اگر ان کی کوئی دلیل ہوتی تو ان کے ماننے
سے مسلمانوں کو ہر گز انکار نہیں ہوسکتا تھا.خلاصہ یہ کہ ایمان بالغیب سے مراد ( 1 ) ان سب صداقتوں پر ایمان لانا ہے جو حواس خمسہ
سے معلوم نہیں کی جاسکتیں بلکہ ان کا ثبوت اور ذرائع سے معلوم ہوتا ہے.جیسے اللہ تعالیٰ کا کلام
ہے جسے مومن سنتے ہیں اور اس کے بتائے ہوئے علوم غیبیہ میں جنہیں مومن پورا ہوتے دیکھتے
ہیں اور اس کی زبر دست قدرتیں ہیں جن کا ظہور مومن اپنے نفوس اور باقی دنیا میں دیکھتے ہیں.مگر
باوجود ان باتوں کے خدا تعالیٰ کی ہستی وراء الوراء ہے وہ حواس خمسہ سے محسوس نہیں کی جاسکتی.اسی طرح ملائکہ کا وجود ہے.ملائکہ ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آتے.منہ دوسرے حواس
ظاہری سے معلوم کئے جا سکتے ہیں.لیکن باوجود اس کے اُن کا وجود وہمی نہیں ہے بلکہ ان کے
وجود پر قطعی دلائل ہیں جو قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر بیان کئے گئے ہیں.یا مثلاً ایک غیب
موت کے بعد کی زندگی ہے قرآن کریم اس پر بے دلیل ایمان لانے کا حکم نہیں دیتا بلکہ اس
کے سچے ہونے پر زبردست دلائل دیتا ہے جو آئندہ مختلف مواقع پر بیان کئے جائیں گے.(2) يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ کے یہ معنے بھی ہیں کہ متقی صرف ایسے کام نہیں کرتے کہ جن کے
نتائج نقد به نقد مل جاتے ہیں.جیسے کہ تاجر سودا فروخت کرتا ہے اور اس کی قیمت وصول کر لیتا
ہے.بلکہ ان کی زندگی اخلاقی زندگی ہوتی ہے اور وہ اخلاق کی قوت اور ان کے نیک نتائج پر
233
Page 242
ایمان رکھتے ہیں اور تاجرانہ ذہنیت کو ترک کر کے ایسی قربانیاں کرتے ہیں کہ جو آخر میں اُن
کی قوم کو اور باقی دنیا کو اُبھار دیتی ہیں.مثلاً دنیا میں امن کے قیام کے لئے جہاد کا کرنا ایمان
بالغیب کا ہی نتیجہ ہے.ورنہ کون جانتا ہے کہ وہ زندہ رہے گا اور لڑائی کے اچھے نتیجہ کو دیکھے گا.سپاہی جب کسی اچھے مقصد کے لئے میدان جنگ میں جاتا ہے تو وہ ایمان بالغیب کا ایک
مظاہرہ کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ وہ اس مقصد کے حصول میں کامیاب ہو گیا تو یہ بھی اچھا ہے.لیکن اگر وہ اس کے لئے جدو جہد کرتے ہوئے مر گیا تب بھی اس کا نتیجہ حق اور صداقت کے
لئے اچھا نکلے گا.حق یہ ہے کہ جس قدر شاندار کام ہیں وہ سب ایمان بالغیب کے نتیجہ میں ہی پیدا ہوتے
ہیں.تعلیم، صدقہ خیرات، غرباء کے اُبھارنے کے لئے کوششیں، ملکی تنظیم، سب ایمان
بالغیب ہی کی اقسام ہیں.اگر انسان آئندہ نکلنے والے اچھے نتائج پر جو ظاہر نگاہ سے پوشیدہ
ہوتے ہیں یقین نہ رکھے تو کبھی ایسی قربانیاں نہ کر سکے.پس متقی کی علامت ایمان بالغیب بتا کر
قرآن کریم نے یہ بتایا ہے کہ مومن ضروری دینی امور پر ایمان رکھنے کے علاوہ اعلیٰ درجہ کی
اخلاقی قربانیاں کرتا ہے اور تاجرانہ ذہنیت سے بالا ہو جاتا ہے اور اس امر پر اصرار نہیں کرتا کہ
میں وہی کام کروں گا جن کا نقد بہ نقد نتیجہ نکلے.بلکہ جب اُسے یقین ہو جائے کہ جو کام اس کے
سامنے پیش کیا گیا ہے اچھا اور نیک ہے تو وہ ظاہری حالات سے بے پروا ہو کر اس یقین سے
اس کام کے کرنے میں لگ جاتا ہے کہ خواہ حالات کتنے ہی مخالف کیوں نہ ہوں نیک کام کا نتیجہ
نیک ہی نکلے گا اور اس امر کی بھی پرواہ نہیں کرتا کہ وہ اس نتیجہ کو خود بھی دیکھے گا یا نہیں.اگر کوئی شخص تعصب سے آزاد ہو کر غور کرے تو ایمان بالغیب کا یہ مفہوم ایسا اہم ہے کہ اس
کے ذریعہ سے قرآن کریم نے تمام قومی، ملی اور بنی نوع انسان کی ترقی کے لئے قربانیوں کی
بنیا درکھ دی ہے.ایک معنے غیب کے غائب ہونے کی حالت کے بھی ہوتے ہیں.ان معنوں کے رُو
سے ایمان بالغیب کے یہ معنے بھی ہیں کہ جب انسان غیب کی حالت میں ہو یعنی لوگوں کی
234
Page 243
نظروں سے پوشیدہ ہو تب بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہو.یعنی اس کا ایمان صرف قومی نہ ہو کہ
جب اس کے ہم مذہب لوگ اس کے سامنے ہوں تب تو وہ ان عقائد کو تسلیم کرے جو اس کے
مذہب نے اس کے سامنے پیش کئے ہیں.لیکن جب وہ اپنے لوگوں سے جُدا ہو تو اس کا ایمان
کمزور ہو جائے.يُقِيمُونَ الصَّلوةَ.اقامة الصلوۃ کے معنے (1) باقاعدگی سے نماز ادا کرنے کے ہیں کیونکہ قام علی
الامر کے معنے کسی چیز پر ہمیشہ قائم رہنے کے ہیں.پس يُقِيمُونَ الصَّلوة کے یہ معنے ہوئے
کہ نماز میں ناغہ نہیں کرتے.ایسی نماز جس میں ناغہ کیا جائے اسلام کے نزدیک نماز ہی نہیں کیونکہ نماز وقتی اعمال سے
نہیں بلکہ اُس وقت مکمل عمل سمجھا جاتا ہے جبکہ تو بہ یا بلوغت کے بعد کی پہلی نماز سے لے کر
وفات سے پہلے کی آخری نماز تک اس فرض میں ناغہ نہ کیا جائے.جولوگ درمیان میں نمازیں
چھوڑتے رہتے ہیں اُن کی سب نمازیں ہی رڈ ہو جاتی ہیں.پس ہر مسلمان کا فرض ہے کہ جب
وہ بالغ ہو یا جب اُسے اللہ تعالیٰ توفیق دے اُس وقت سے موت تک نماز کا ناغہ نہ کرے کیونکہ
نماز خدا تعالیٰ کی زیارت کا قائم مقام ہے اور جو شخص اپنے محبوب کی زیارت سے گریز کرتا ہے
وہ اپنے عشق کے دعوی کے خلاف خود ہی ڈگری دیتا ہے.(2) دوسرے معنے اقامة کے اعتدال اور درستی کے ہیں.ان معنوں کے رُو سے
يُقِيمُونَ الصَّلوةَ کے یہ معنے ہیں کہ متقی نماز کو اُس کی ظاہری شرائط کے مطابق ادا کرتے ہیں
اور اس کے لئے جو قواعد مقرر کئے گئے ہیں ان کو توڑتے نہیں.مثلاً تندرستی میں یا پانی کی
موجودگی میں وضو کر کے نماز پڑھتے ہیں اور وضو بھی ٹھیک طرح ان شرائط کے مطابق ادا کرتے
ہیں جو اس کے لئے شریعت نے مقرر کی ہیں.اسی طرح صحیح اوقات میں نما زادا کرتے ہیں.نماز میں قیام، رکوع، سجدہ اور قعدہ کو عمدگی سے ادا کرتے ہیں.مقررہ عبارات اور دعائیں اور
تلاوت اپنے اپنے موقع پر اچھی طرح اور عمدگی سے پڑھتے ہیں.غرض تمام ظاہری شرائط کا
235
Page 244
خیال رکھتے اور انہیں اچھی طرح بجالاتے ہیں.اس جگہ یا درکھنا چاہئے کہ گو شریعت کا حکم ہے کہ نماز کو اس کی مقررہ شرائط کے ماتحت ادا
کیا جائے مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ جب مجبوری ہو اورشرائط پوری نہ ہوتی ہوں تو نما ز کوترک
ہی کر دے.نماز بہر حال شرائط سے مقدم ہے.اگر کسی کو صاف کپڑا میسر نہ ہو تو وہ گندے
کپڑوں میں ہی نماز پڑھ سکتا ہے خصوصاً وہم کی بناء پر نماز کا ترک تو بالکل غیر معقول ہے.جیسا
کہ ہمارے ملک میں کئی عورتیں اس وجہ سے نماز ترک کر دیتی ہیں کہ بچوں کی وجہ سے کپڑے
مشتبہ ہیں.اور کئی مسافر نماز ترک کر دیتے ہیں کہ سفر میں طہارت کامل نہیں ہوسکتی.یہ سب
شیطانی وساوس ہیں لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا (بقرہ 287) البہی حکم ہے.جب تک
شرائط کا پورا کرنا اختیار میں ہو اُن کے ترک میں گناہ ہے.لیکن جب شرائط پوری کی ہی نہ جاسکتی
ہوں تو اُن کے میسر نہ آنے کی وجہ سے
نماز کا ترک گناہ ہے اور ایسا شخص معذور نہیں بلکہ نماز کا
تارک سمجھا جائے گا.پس اس بارہ میں مومنوں کو خاص طور پر ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے.(3) تیسرے معنے اقامہ کے کھڑا کرنے کے ہیں ان معنوں کے رُو سے يُقِيمُونَ
الصَّلوة کے معنے یہ ہوئے کہ وہ نماز کو گرنے نہیں دیتے.یعنی ہمیشہ اس کوشش میں رہتے
ہیں کہ ان کی نماز درست اور با شرائط ادا ہو.اس میں ان مشکلات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ
جو نماز پڑھنے والے مبتدی کو زیادہ اور عارف کو کسی کسی وقت پیش آتی رہتی ہیں.یعنی اندرونی
یا بیرونی تاثرات نماز سے توجہ ہٹا کر دوسرے خیالات میں پھنسا دیتے ہیں.یہ امر انسانی عادت
میں داخل ہے کہ اس کا خیال مختلف جہات کی طرف منتقل ہوتا رہتا ہے اور خاص صدموں یا
جوش یا محبت کے اثر کے سوا جبکہ ایک وقت تک خیالات میں کامل یکسوئی پیدا ہو جاتی ہے
انسانی دماغ ادھر اُدھر گھومتا رہتا ہے اور ایک خیال سے دوسرا خیال پیدا ہو کر ابتدائی خیال
سے کہیں کا کہیں لے جاتا ہے.اسی طرح بیرونی آوازیں یا پاس کے لوگوں کی حرکات یا کھٹکے،
بو یا خوشبو، جگہ کی سختی یا نرمی اور اسی قسم کے اور امور انسانی ذہن کو ادھر سے اُدھر پھرا دیتے
ہیں.یہی مشکلات نمازی کو پیش آتی ہیں اور اگر اپنے خیالات پر پورا قابو نہ ہو تو اسے پریشان
236
Page 245
خیال بنائے رکھتی ہیں اور بعض اوقات وہ نماز کے مضمون کو بھول کر دوسرے خیالات میں
پھنس جاتا ہے.اس حالت کی نسبت يُقِيمُونَ الصَّلوۃ میں اشارہ کیا ہے اور فرمایا ہے کہ
بعض نمازیوں کو یہ مشکل پیش آئے گی مگر انہیں گھبرانا نہیں چاہئے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر درجہ
کے انسان کے لئے ترقی کا راستہ کھول دیا ہے.اگر کوئی شخص اپنی نماز میں ایسی پریشان خیالی
سے دو چار ہو تو اسے مایوس نہیں ہونا چاہئے اور اپنی نماز کو بریکار نہیں سمجھنا چاہئے کیونکہ اللہ تعالیٰ
بندوں سے اُسی قدر قربانی کی امید کرتا ہے جتنی قربانی اُن کے بس کی ہو.پس ایسے نمازی جن
کے خیالات پراگندہ ہو جاتے ہوں اگر نماز کو سنوار کر اور توجہ سے پڑھنے کی کوشش میں لگے
رہیں تو چونکہ وہ اپنی نماز کو جب بھی وہ اپنے مقام سے گرے کھڑا کرنے کی کوشش میں لگے
رہیں گے اللہ تعالیٰ ان کی نماز کو ضائع نہیں کرے گا بلکہ اُسے قبول کرے گا اور اس نماز کو کھڑا
کرنے کی کوشش کرنے والے کو متقیوں میں ہی شامل سمجھے گا.(4) يُقِيمُونَ الصَّلوة کے ایک اور معنے بھی ہیں اور وہ یہ کہ متقی دوسرے لوگوں کو نماز کی
ترغیب دیتے ہیں کیونکہ کسی کام کو کھڑا کرنے کا ایک طریق یہ بھی ہے کہ اسے رائج کیا جائے اور
لوگوں کو اس کی ترغیب دلائی جائے.پس يُقِيمُونَ الصَّلوة کے عامل متقی وہ بھی کہلائیں گے کہ جو
خود نماز پڑھنے کے علاوہ دوسرے لوگوں کو بھی نماز کی تلقین کرتے رہتے ہیں اور جوست ہیں انہیں
تحریک کر کے چست کرتے ہیں.رمضان کے موقع پر جولوگ تہجد کے لئے لوگوں کو جگاتے ہیں
وہ بھی اس تعریف کے ماتحت يُقِيمُونَ الصَّلوة کی تعریف میں آتے ہیں.(5) نماز با جماعت سے پہلے امام کے نماز پڑھانے کے قریب وقت میں اذان کے
کلمات تھوڑی زیادتی کے ساتھ دہرائے جاتے ہیں.ان کلمات کو اقامة کہتے ہیں اور نماز
باجماعت بھی ان معنوں کے رُو سے اقامة الصلوة کا مفہوم رکھتی ہے.ہمارے ملک میں بھی
کہتے ہیں نماز کھڑی ہوگئی ہے.اس محاورہ کے مطابق يُقِيمُونَ الصَّلوة کے معنے ہوں گے کہ
وہ نماز باجماعت ادا کرتے ہیں اور دوسروں سے ادا کرواتے ہیں.قرآن کریم میں نماز پڑھنے کا جہاں بھی حکم آیا ہے آقِیمُوا الصَّلوة کے الفاظ سے آیا ہے
237
Page 246
کبھی بھی خالی صلوا کے الفاظ استعمال نہیں ہوئے.یہ امر اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اصل
حکم یہ ہے کہ فرض نماز کو باجماعت ادا کیا جائے اور بغیر جماعت کے نما ز صرف مجبوری کے
ما تحت جائز ہے.جیسے کوئی کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھ سکے تو اُسے بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت ہے.پس جس طرح کوئی کھڑا ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت رکھتا ہولیکن بیٹھ کر پڑھے تو یقیناً وہ گنہگار ہوگا
اسی طرح جسے باجماعت نماز کا موقع مل سکے مگر وہ باجماعت نماز ادا نہ کرے تو وہ بھی گنہگار ہوگا.(6) يُقِيمُونَ الصَّلوة کے ایک معنے یہ بھی ہیں کہ نماز چستی اور ہوشیاری سے ادا کی
جائے کیونکہ سستی اور غفلت کی وجہ سے خیالات میں پراگندگی پیدا ہوتی ہے اور نماز کا مغز ہاتھ
سے جاتا رہتا ہے.اسی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں لاتیں ڈھیلی چھوڑنے
یا سہارا لگانے (مسلم جلد اول كتاب الصلوة باب كراهة الاختصار في الصلوة) يا
کہنیاں سجدہ کے وقت زمین پر ٹیکنے سے منع فرمایا ہے (ترمذی ابواب الصلوۃ باب ماجاء
في الاعتدال في السجود) اور اس کے بالمقابل رکوع میں کمر سیدھی رکھنے (ترمذی ابواب
الصلوة باب ماجاء فی من لایقیم (صلبه) کھڑا ہوتے وقت یا رکوع میں ٹانگوں کو سیدھا
رکھنے ،سجدہ میں پاؤں ، گھٹنوں ہتھیلیوں اور ماتھے پر بوجھ رکھنے (ترمذی کتاب الصلوۃ باب
ماجاء في السجود على سبعة اعضاء) اور کمر اور پیٹ کو لاتوں سے جدا رکھنے (نسائی کتاب
افتتاح الصلوة باب صفة السجود و التجافى السجودو الاعتدال فی السجود) اور قعدہ
کے موقع پر دائیں پاؤں کی انگلیوں کو قبلہ رخ رکھ کر پاؤں کھڑا رکھنے کا حکم دیا ہے (ترمذی
ابواب الصلوۃ باب ماجاء كيف الجلوس التشهد) کیونکہ یہ سب امور چستی اور ہوشیاری
پیدا کرتے ہیں اور نیند اور اُونگھ اور غفلت کو دور کرتے ہیں اور اسی وجہ سے اسلام نے نماز سے
پہلے وضو کرنے کا حکم دیا ہے تا کہ سر اور جوارح کے اعصاب کوتری اور سردی پہنچ کر جسم میں
چستی اور خیالات میں یکسوئی پیدا ہو.اوپر جو معانی یقیمُونَ الصَّلوةَ کے لغوی معنوں سے استنباط کر کے لکھے گئے ہیں قرآن
کریم اور احادیث سے بھی ان کی تصدیق ہوتی ہے.238
Page 247
بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو عبادت کا حکم دینے سے کیا فائدہ؟ کیا وہ
بندوں کی عبادت کا محتاج ہے؟ تعظیم اور تکریم سے تو نادان انسان خوش ہوا کرتے ہیں.خدا تعالیٰ کی ذات کو تو اس سے ارفع ہونا چاہئے؟
اس کا جواب یہ ہے کہ عبادت کا فائدہ یہ نہیں کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی شان بڑھتی ہے بلکہ
عبادت کی غرض اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان ایسا اتصال پیدا کرنا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے
ٹور کو اپنے اندر اخذ کر لے.اس حقیقت کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ صرف فکر انسان کے اندر وہ
جذ بہ نہیں پیدا کر سکتا جس سے وہ خدا تعالیٰ کی ذات میں اپنے آپ کو محو کرنے کی کوشش
کرے.ایسا جذ بہ تو محبت کامل سے ہی پیدا ہو سکتا ہے اور محبت کامل محسن ہستی کے احسانوں
کے کامل انکشاف سے پیدا ہوتی ہے اور نماز اس غرض کو پورا کرتی ہے کیونکہ نماز میں اللہ تعالیٰ
کی حقیقی شان کو سامنے لانے کے سامان مہیا کئے جاتے ہیں.اگر کہو کہ جو انسان خدا تعالیٰ کی محبت پیدا کرنا چاہے گا وہ خود ہی اپنے لئے اس کا موقع نکال
لے گا اس کے لئے پانچ وقت کی نماز مقرر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟
تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اعتراض قلت تدبر سے پیدا ہوا ہے.انسانی طبیعت اس قسم کی
ہے کہ اگر باقاعدگی سے اسے اس کے مقصد کی طرف توجہ نہ دلائی جائے تو وہ سستی کرنے لگتا
ہے.پس اللہ تعالیٰ نے کمزور اور قوی سب کو اس اعلیٰ مقام تک پہنچانے کے لئے نماز
باجماعت ادا کرنے کا حکم دیا ہے تا کہ کمزور بھی قوی کے ساتھ مل کر ان مواقع کو پاتے رہیں جو
ان کے دلوں کے اندر صفائی پیدا کریں اور قومی ایمان والوں کے دلوں سے نکلنے والی مخفی
تاثیرات کو اپنے اندر جذب کر کے صفائی قلب پیدا کرسکیں.بعض لوگ کہتے ہیں کہ پانچ وقت کی نماز کا کیوں حکم دیا گیا ہے حالانکہ اس زمانہ میں
مشاغل اس قدر بڑھ گئے ہیں کہ اتنا وقت نمازوں کے لئے نکالنا مشکل ہے؟
اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ اگر نماز کی غرض محبت الہی کی آگ بھڑکا کر اللہ تعالیٰ کی
صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لئے سہولت بہم پہنچانا ہے تو جس زمانہ میں مشاغل بڑھ
239
Page 248
جائیں اس زمانہ میں نماز کی ضرورت بڑھ جاتی ہے، نہ کہ کم ہو جاتی ہے.اگر نما ز صرف ایک اظہار عقیدہ کا ذریعہ ہوتا تب یہ اعتراض کچھ وزن بھی رکھتا.مگر جیسا کہ
بتایا گیا ہے نماز کی غرض صرف اقرار عبودیت نہیں بلکہ اس کی غرض تو انسانی نفس میں وہ
استعداد پیدا کرنا ہے جس کی مدد سے وہ مادی دنیا سے اڑ کر روحانی عالم میں پہنچ سکے اور اس کا
دماغ جسمانی خواہشات میں ہی الجھ کر نہ رہ جائے بلکہ اعلیٰ اخلاق کو حاصل کرے.جیسا کہ
قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اِنَّ الصَّلوةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
(العنكبوت (46) یعنی نماز صرف عبودیت کا اقرار نہیں بلکہ قلب انسانی کو جلا دینے والی شے
ہے اور اس کی مدد سے انسان بدیوں اور بد کرداریوں سے بچتا ہے اور اس کا وجود بنی نوع انسان
کے لئے مفید بنتا ہے اور وہ ملت وقوم کا ایک فائدہ بخش جزو ہو جاتا ہے.پس جو عمل کہ یہ
خوبیاں رکھتا ہو مادی اشغال کی کثرت کے زمانہ میں اس کی ضرورت کم نہیں ہوتی بلکہ بہت
بڑھ جاتی ہے.اور حق تو یہ ہے کہ اس زمانہ میں بدامنی اور شورش اور نفسانفسی اور قوموں کی
قوموں پر چڑھائی کا اصل سبب یہی ہے کہ لوگ سچی عبادت میں کوتاہی کرنے لگے ہیں ورنہ
اگر صحیح عبادت کا طریق لوگوں میں رائج ہوتا تو اس دُنیا کو پیدا کرنے والے مہر بان آقا سے
اتصال کی وجہ سے بغض اور نفرت کی جگہ محبت اور ایثار اور قربانی کا جذبہ پیدا ہوتا.وَما رَزَقُهُم يُنفِقُونَ کے معنے یہ ہیں کہ جو کچھ بھی تم کو ہم نے دیا ہو.خواہ علم ہو،
عزت ہو، عقل ہو، مال ہو، دولت ہو، اس میں سے ایک حصہ تم کو خرچ کرنا چاہئے.پس اس
جملہ کے یہ معنے نہیں کہ جو کچھ تم کو کھانے پینے کی اشیاء ملی میں ان میں سے کچھ غریبوں کو بھی
کھلاؤ.کیونکہ نہ تو اس جملہ میں غریبوں کا ذکر ہے نہ اس چیز کی تعیین ہے جسے خرچ کرنا ہے.اور ہمارا کوئی حق نہیں کہ جن اشیاء کو خدا تعالیٰ نے بغیر حد بندی کے چھوڑ دیا ہے ہم ان کے لئے
اپنے پاس سے حد بندی مقرر کریں.اللہ تعالیٰ اس آیت میں صرف اس قدر فرماتا ہے کہ جو کچھ ہم نے تمہاری ضرورتوں کے
مطابق دیا ہے اسے خرچ کرو.یہ ضرورت کے مطابق ملنے والی چیز علم بھی ہوسکتا ہے.عقل
240
Page 249
بھی ، جرأت بھی، غیرت بھی ، وفا بھی، ہاتھ پاؤں کی خدمت بھی ، آنکھ ناک کی خدمت بھی ،
روپیہ پیسہ کی خدمت بھی.غرض کوئی چیز جس کی نسبت کہا جاسکے کہ خدا تعالیٰ نے دی ہے اور
کسی ضرورت کے پورا کرنے کے لئے دی ہے اس کے خرچ کرنے کا حکم ہے.اور اگر کوئی
شخص ایسا ہو کہ روپیہ تو دوسروں کو امداد کے طور پر دیتا ہولیکن مثلاً کھانانہ دیتا ہو یا کھانا دیتا ہو
کپڑا نہ دیتا ہو یا کپڑا تو دیتا ہولیکن مکان نہ دیتا ہو یا مکان تو دیتا ہومگر اپنے ہاتھوں سے خدمت
نہ کرتا ہو یا ہاتھوں سے خدمت تو کرتا ہو مگر اپنے علم سے لوگوں کو فائدہ نہ پہنچا تا ہو تو وہ اس آیت
پر پوری طرح عامل نہ سمجھا جائے گا.اور اسی طرح اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ وہی
اس آیت پر عامل نہیں جو غریبوں کو روپیہ دیتا ہے بلکہ وہ بھی عامل ہے جولوگوں کو علم پڑھاتا
ہے اور وہ بھی عامل ہے جو مثلاً بیواؤں یتیموں کے کام کر دیتا ہے اور وہ سپاہی بھی عامل ہے جو
میدانِ جنگ میں ملک کی خاطر جان دینے کی نیت سے جاتا ہے اور وہ موجد بھی عامل ہے جو
رات دن کی محنت سے دنیا کے فائدہ کے لئے کوئی ایجاد کرتا ہے.ہر وہ شخص جو اپنے نفس کے بارہ میں بخل سے کام لیتا ہے اور ضرورت اور صحت کے
مطابق کھانا نہیں کھاتا وہ اس حکم کو توڑنے والا ہے خواہ وہ دوسروں پر کس قدر ہی کیوں نہ خرچ
کرے کیونکہ یہ آیت یہ نہیں کہتی کہ غریبوں پر خرچ کرو بلکہ یہ آیت خرچ کرنے کے مقام کو
ہلا تعیین چھوڑ کر خود انسان کے نفس کو بھی اس میں شامل کرتی ہے اور اس کی بیوی کو بھی اور اس
کے بچے کو بھی اور اس کے دوستوں کو بھی.اس آیت سے یہ بھی استدلال ہوتا ہے کہ خدا کے دیئے ہوئے میں سے کچھ حصہ خرچ
کرنے کا حکم ہے نہ یہ کہ سب ہی خرچ کر دے.حمد اس جگہ یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ تمام مال کا خرچ تو بُرا کہلا سکتا ہے مگر اس آیت میں
تو علم اور فہم وغیرہ کے اخراجات کو بھی شامل کیا گیا ہے.ان چیزوں میں سے کچھ خرچ کرنے
کے کیا معنے ہیں؟ کیا انسان اپنا سارا علم لوگوں کو نہ سکھائے یا اپنی عقل سے پوری طرح لوگوں کو
فائدہ نہ پہنچائے ؟
241
Page 250
تو اس کا جواب یہ ہے کہ علم اور فہم اور عقل خرچ کرنے سے بڑھتے ہیں.پس ان میں سے کچھ
خرچ کرنے کے یہ معنی ہیں کہ اس طرح علم سے لوگوں کو فائدہ نہ پہنچائے یا نہم سے یا عقل سے کہ
ان کے بڑھنے کا منبع خراب ہو جائے.مثلاً یہ ہلاک ہو جائے یا اس کی صحت ایسی طرح بگڑ جائے کہ
اس کا علم یا فہم یا عقل کام دینے سے رُک جائیں.مثلاً دماغ خراب ہو جائے.غرض علم اور فہم اور عقل
کا بھی اسی قدر استعمال ہونا چاہئے کہ ان کا چشمہ نہ سوکھ جائے.کیونکہ جو شخص اپنے علم اور عقل سے
لوگوں کو اس طرح فائدہ پہنچاتا ہے یا اپنے آپ کو اس طرح فائدہ پہنچاتا ہے کہ ان کے منبع میں
خرابی واقع ہو جاتی ہے وہ اس آیت کے حکم کے خلاف عمل کرتا ہے.م اگر کہا جائے کہ کیا سارا مال خدا کی راہ میں خرچ کرنے والا گنہگار ہوگا ؟
تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح علم اور فہم اور عقل کا منبع ہوتا ہے اور وہ اس کا راس المال
ہوتا ہے اسی طرح مال کا بھی ایک منبع ہوتا ہے.پس سارا مال خرچ کرنے سے یہی مراد ہوگی
کہ وہ اس منبع تک کو خرچ نہ کر دے.ما رَزَقُهُمْ يُنْفِقُونَ سے یہ بھی استدلال ہوتا ہے کہ انسان کو حلال اشیاء خرچ کرنی
چاہئیں.یہ نیکی نہیں کہ حرام مال یا حرام اشیاء خرچ کرے.بعض لوگ رشوتیں لے کر اور بعض
ڈاکے ڈال کر مال جمع کرتے ہیں اور غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ نیکی کرتے
ہیں.حالانکہ بدی سے بدی پیدا ہو سکتی ہے، نیکی نہیں.ایسے لوگ بدیوں کی بنیادر کھتے ہیں.ان
کا صرف اس قدر کام تھا کہ جو خدا تعالیٰ نے ان کو دیا تھا اس میں سے خرچ کرتے.اگر کوئی
شخص دوسرے کے مال سے جس پر اس کا حق نہیں دوسرے کو کچھ دے دیتا ہے وہ اس حکم کا
پورا کرنے والا نہیں کہلا سکتا.کیونکہ وہ اُس رزق میں سے خرچ نہیں کرتا جو خدا تعالیٰ نے اسے
دیا تھا بلکہ اس میں سے خرچ کرتا ہے جو خدا تعالیٰ نے اسے نہیں دیا تھا.اور یہ آیت کہتی ہے
کہ جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں.شاید کوئی اعتراض کرے کہ خدا تعالیٰ کو اس کی کیا ضرورت پیش آئی کہ بندوں کی
وساطت سے دوسروں پر خرچ کروائے ؟ کیوں نہ اس نے سب انسانوں کو براہ راست ان کا
242
Page 251
حصہ دے دیا ؟
تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ محض قلت تدبر کا نتیجہ ہے کہ خیال کیا جاتا ہے کہ بعض لوگ
خرچ کرنے والے ہیں اور بعض دوسروں کی امداد پر گزارہ کرتے ہیں کیونکہ درحقیقت سب ہی
لوگ ایک دوسرے پر خرچ کرنے والے ہیں.اس جگہ ایک اور نکتہ بھی یادرکھنے کے قابل ہے اور وہ یہ ہے کہ اقامة الصلوۃ کو اس
جگہ پہلے رکھا گیا ہے اور مما رَزَقُهُمْ يُنْفِقُونَ کو بعد میں رکھا گیا ہے.اس سے اس طرف
اشارہ ہے کہ رُوحانی عالم میں خدا تعالیٰ سے تعلق مخلوق سے تعلق پر مقدم ہے اور یہی طبعی اور درست
ترتیب ہے.کیونکہ بغیر اللہ تعالیٰ سے کامل تعلق کے مخلوق سے کامل محبت ہو ہی نہیں سکتی.وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالآخِرَةِ
هُمْ يُوقِنُونَ
اس آیت میں متقیوں کی تین اور صفات بیان کی گئی ہیں اور اس آیت کی پہلی اور گزشتہ
آیت کو ملا کر چوتھی علامت متقی کی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بیان فرمائی ہے کہ جو کلام
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے متقی اس پر ایمان لاتے ہیں.چونکہ روحانی عالم میں صحیح طریق عمل وہی ہے کہ جو خدا تعالی کی طرف سے بتایا جائے اس
لئے وہی شخص نیک نیت کہلائے گا کہ جو اس طریق کو معلوم کرنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی
کوشش کرے.اور چونکہ قرآن کریم کا دعویٰ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے
بعد وہی صحیح طریق عمل ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی آپ پر ظاہر کیا ہے.اس لئے وہی
شخص روحانی مقاصد کو پا سکتا ہے جو آپ پر نازل ہونے والے کلام پر ایمان لائے.پس چوتھی صفت متقی کی یہ بیان کی گئی کہ وہ آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے
والے کلام پر ایمان لاتا ہو.کیونکہ جو شخص اس کلام پر ایمان نہیں لاتا جو اس کے زمانہ کی
ہدایت کے لئے نازل ہوا ہو وہ ہدایت کی جزئیات سے نہ باخبر ہوسکتا ہے اور نہ اُن پر عمل کر
سکتا ہے.243
Page 252
بعض لوگ اس آیت اور ایسی ہی بعض دوسری آیات سے یہ دھوکا کھاتے ہیں کہ قرآن
کریم پر ایمان لانے کا حکم ہے نہ کہ محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم پر.اس لئے محمد رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کی کسی بات
کو تسلیم کرنے کی نہ ضرورت ہے نہ یہ جائز ہے بلکہ شرک ہے.ان لوگوں کو یہ دھو کا قرآن کریم کے مضامین پر غور نہ کرنے سے لگا ہے.اس جگہ ایک اور مضمون بھی وضاحت طلب ہے اور وہ کلام کے اتارنے کا محاورہ
ہے.عام طور پر جب اسلامی تعلیم سے ناواقف لوگ کلام الہی کے اترنے کا محاورہ قرآن کریم
میں پڑھتے ہیں تو خیال کر لیتے ہیں کہ شائد یہ کلام خدا تعالیٰ نے لکھ کر فرشتوں کو دیا اور وہ اسے
آسمان پر سے زمین پر لائے اور رسول کے ہاتھ میں دے دیا.بلکہ غیر مذہب والوں کو کیا کہنا
ہے خود مسلمانوں میں سے ایک بڑا طبقہ تعلیم اسلام سے ناواقفی کی وجہ سے اب یہی سمجھنے لگ گیا
ہے کہ شائد کوئی چیز آسمان پر سے زمین پر مادی طور پر اترتی ہے اور رسول کو ملتی ہے.لیکن یہ
عقیدہ کئی غلطیوں کے نتیجہ میں پیدا ہوا ہے (1) ان لوگوں نے غور نہیں کیا کہ آسمان سے کیا مراد
ہے؟ (2) انہوں نے غور نہیں کیا کہ فرشتے کیا ہیں اور ان کے اعمال کس طرح ظاہر ہوتے
ہیں؟ ( 3) انہوں نے یہ غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کس ذریعہ سے ظہور پذیر ہوتے
ہیں؟ ( 4 ) انہوں نے غور نہیں کیا کہ نزول کے کیا معنے ہیں؟ ان چار امور پر غور نہ کرنے کے
سبب سے ان کو مذکورہ بالا غلط عقیدہ میں مبتلا ہونا پڑا ہے.وَمَا أُنْزِلَ مِن قَبْلِكَ.پہلی آیت کو شامل کر کے پانچویں اور اس آیت میں بیان کردہ
دوسری علامت متقیوں کی یہ بتائی کہ وہ ان وحیوں پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آ نحضرت صلے اللہ
علیہ وسلم سے پہلے نازل ہو چکی ہیں.(1) قرآن کریم میں پہلے کلاموں پر ایمان کو بعد میں رکھا گیا ہے.پہلی وحی کا بعد میں
ذکر کرنا بتاتا ہے کہ اس پر ایمان قرآن کریم کے توسط سے ہے.یعنی اس کے بتائے ہوئے
اصول کے مطابق.244
Page 253
(2) وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ میں کسی قوم یا مذہب کا مخصوص ذکر نہیں بلکہ ہر قوم وملت کے
الہام کی تصدیق کی ہے.بعض مسلمان اس غلطی میں مبتلا ہیں کہ رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی کا نزول
کس طرح ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ وہم اُن کا قرآنی تعلیم کے خلاف ہے.قرآن کریم میں اللہ
تعالیٰ صاف طور پر مسلمانوں کی نسبت فرماتا ہے اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا
تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَئِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَابْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُوْنَ (حم
سجدة 31) یعنی جو مسلمان یہ اعلان کر کے کہ اللہ ہمارا رب ہے تمام مصائب کو برداشت کریں
گے اور استقامت دکھائیں گے خدا تعالیٰ کے فرشتے ان پر یہ کہتے ہوئے نازل ہوں گے کہ نہ
آئندہ کا خوف کرو اور نہ سابق پر غم کرو اور اس جنت کی بشارت سنو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا
تھا.اسی طرح قرآن کریم میں آتا ہے.وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُوْلَ فَأُوْلَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ
اللهُ عَلَيْهِم مِنَ النَّبينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ
رفِيقًا (النساء (70) یعنی جو لوگ اللہ اور رسول ( یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) کی
اطاعت کریں گے وہ اس گروہ میں شامل ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے.یعنی
نبیوں صدیقوں شہداء اور صالحین کے گروہ میں اور یہ گروہ ساتھیوں کے لحاظ سے سب سے بہتر
گروہ ہے.پس جبکہ اس اُمت سے یہ وعدہ ہے کہ وہ نبیوں اور صدیقوں اور شہداء والے انعام
پائے گی تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اس امت میں وحی الہی کا دروازہ بند ہو.اصل انعام جو
نبیوں اور صدیقوں اور شہداء کو ملتا ہے وہ تو خدا تعالیٰ کی وحی ہی ہے.اس آیت میں اس پیشگوئی کی طرف بھی اشارہ ہے جو سورۃ جمعہ میں کی گئی ہے.اللہ تعالیٰ
فرماتا ہے هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَب وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَلٍ مُّبِينٍ وَآخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا
يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (الجمعة 4-3) یعنی وہ خدا ہی ہے جس نے امتیوں میں انہی
245
Page 254
کی قوم کا ایک رسول بھیجا جو انہیں اس کی آیات پڑھ کر سُناتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور
انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے گو پہلے وہ پھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے.اور اسی طرح وہ
ان کے سوا ایک اور قوم کو سکھائے گا جو اب تک انہیں نہیں ملے.اور اللہ غالب اور حکمت والا
ہے.جب یہ آیت نازل ہوئی تو احادیث میں آتا ہے کہ صحابہ نے پوچھا وہ کون لوگ ہیں جن
کا اس آیت میں ذکر ہے جو ہم سے نہیں ملے؟ اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت
سلمان فارسی کے سر پر ہاتھ رکھ کر فرمایا لو كان الدين عِنْدَ القُرَيَا لَذَهَبَ رَجُلٌ مِنْ فَارِسَ أَوْ
ابناء فَارِسَ حَتى يَتَنَاوَلَة (مسند احمد بن حنبل جلد دوم صفحه 309) که اگر ایمان
ثریا پر بھی چڑھ جائے تو فارس سے ایک شخص یا فرما یا ابناء فارس میں سے ایک شخص آسمان پر جا
کر دین کو واپس لے آئے گا.اس روایت سے اور بعض اور روایات سے کہ جن میں رجُل کی
جگہ رجال کا لفظ ہے (بخاری جلد سوم کتاب التفسیر معلوم ہوتا ہے کہ ایک زمانہ میں
ایمان دنیا سے اُٹھ جائے گا اور ایک شخص بنو فارس سے جس کے ساتھ اور بھی بعض ابناء فارس
بطور مد گار ہوں گے ایمان کو واپس لائے گا اور اس کی معرفت اللہ تعالیٰ پھر رسول کریم صلی اللہ
علیہ وسلم کو وہی کام کرنے کا موقع دے گا کہ جو صحابہ کے زمانہ میں آپ نے کیا.یعنی وہ آپ کا
بروز ہونے کی حیثیت سے خدا تعالیٰ کی وحی سے اصلاح امت کرے گا.غرض اس آیت کے سباق کو مد نظر رکھتے ہوئے و بالا خِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ کے معنے یہ ہیں کہ
جس طرح متقی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی پر ایمان رکھتا ہے اور آپ سے پہلی وحی پر
ایمان رکھتا ہے اسی طرح وہ بعد میں آنے والی وحی پر بھی یقین رکھتا ہے.شاید کسی کو یہ شبہ گزرے کہ پہلی دونوں وحیوں کی نسبت تو ایمان کا لفظ استعمال ہوا ہے
لیکن آخرۃ کی نسبت یقین کا لفظ استعمال ہوا ہے.پس کیوں نہ سمجھا جائے کہ اس جگہ وحی کی
بجائے کسی اور چیز کا ذکر ہے ورنہ اس کے لئے بھی ایمان کا لفظ استعمال ہوتا ؟
اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ ایمان کا لفظ عام طور پر اُس شے کے متعلق استعمال ہوتا ہے جس کا
246
Page 255
وجود معرض وجود میں آچکا ہو.جس کا وجود معرض وجود میں نہ آیا ہو بلکہ آئندہ آنے والا ہو اس کی
نسبت یقین کا لفظ ہی زیادہ مناسب ہوتا ہے.اگر کہا جائے کہ حیات بعد الموت کے متعلق بھی تو ایمان کا لفظ آتا ہے حالانکہ وہ بعد میں
آنے والی شے ہے.تو اس کا جواب یہ ہے کہ حیات بعد الموت بیشک ایک زندہ شخص کے
لئے تو بعد میں آنے والی شے ہے مگر اس کا وجود اس وقت بھی موجود ہے.اور جولوگ مر چکے
ہیں وہ معا ایک قسم کی زندگی پارہے ہیں.پس یہ خدائی فعل پہلے بھی ظاہر ہوتا رہا ہے، اب بھی
ہو رہا ہے اور آئندہ بھی ہوتا رہے گا.پس حیات بعد الموت در حقیقت ایک ایسی چیز ہے جو ہر
وقت ہورہی ہے اس لئے اس کی نسبت ایمان کا لفظ ہی زیادہ مناسب ہے.مگر جو وحی آئندہ
نازل ہونے والی ہو اس کی نسبت یقین کا لفظ زیادہ مناسب ہے.اگر پہلی وحیوں کی نسبت سے وحی کا ذکر نہ کیا جائے بلکہ صرف یہ کہا جائے کہ مومن اس امر
کو تسلیم کرتے ہیں کہ وحی خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی ہے تو اس موقعہ پر چونکہ مخصوص
طور پر آئندہ وحی کا ذکر نہ ہوگا اس کے لئے ایمان کا لفظ زیادہ مناسب ہوگا.اصل بات یہ ہے کہ وحی الہی ہر شخص پر نہیں اترتی بلکہ بعض ترقی یافتہ اور مقرب وجودوں پر
اُترتی ہے اور قومی لحاظ سے متقیوں کا فرض مقرر کیا گیا ہے کہ وہ اس امر پر یقین رکھیں کہ
اللہ تعالی آئندہ بھی ان کو بھلائے گا نہیں بلکہ ان میں سے کامل وجودوں پر وحی نازل ہوتی رہے
گی.اور اس طرح ہر مسلمان کے دل میں یہ خواہش پیدا کی گئی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایسا اعلی
درجہ کا متقی بنائے کہ اس پر خدا تعالیٰ کی وحی نازل ہو اور اس طرح اعلیٰ امید پیدا کر کے اور اعلیٰ
مقصد کو سامنے لا کر مسلمانوں
کا مطمح نظر اونچا کردیا گیا ہے.بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ وحی مذکر ہے اور آخرۃ مؤنث کا صیغہ ہے پھر
اس سے وحی کی طرف کس طرح اشارہ ہوا ؟
اس کا جواب یہ ہے کہ اس جگہ وحی کا لفظ نہیں ما اُنْزِل کے الفاظ ہیں اور ان کی تعبیر کسی
247
Page 256
ہم معنے لفظ سے کی جاسکتی ہے.قرآن کریم میں بما انزل کے لفظ کی تعبیر وحی سے بھی کی گئی ہے
اور رسالہ کے لفظ سے بھی.چنانچہ سورۃ احزاب میں ہے الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسُلَتِ اللهِ
وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا الله الاحزاب (40) یعنی وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی وحی لوگوں
تک پہنچاتے ہیں اور اس سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے.غرض
رسالت کا لفظ بھی وحی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے اور یہ لفظ مؤنث ہے.پس آخرت کے
معنى الرسالة الأخرةُ کے ہیں.اور رسالۃ کے لفظ کی رعایت سے اخرة کا لفظ مؤنث آیا
ہے.یادر ہے کہ لغت میں بھی وحی کے معنے رسالت کے آتے ہیں.( تاج العروس )
أوليك على هدى من ربهم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.فلاح کے معنے کسی کام میں کامیابی اور مقصود کو پالینے کے ہیں (مفردات)
ہر اس شخص کو جو کسی دنیوی یا دینی بھلائی کو حاصل کرے مُفلح کہتے ہیں.اور فلاح ایسی
کامیابی کو کہتے ہیں جس پر دوسرے رشک کریں.حمد اس آیت میں من رسم کے الفاظ استعمال کر کے یہ بتایا ہے کہ خدا تعالیٰ چونکہ رب
ہے اور رب اسے کہتے ہیں جو بتدریج ترقی کی طرف لے جائے اس لئے جو شخص خدا تعالیٰ سے
تعلق پیدا کرے اس کا قدم بتدریج آگے کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے.دوسرے رب کو ھم کی
طرف مضاف کر کے یہ بتایا ہے کہ خدا تعالیٰ چونکہ ان کا رب ہے اس لئے اصل منشاء اس کا یہ
ہے کہ لوگ ہدایت پائیں، نہ یہ کہ گمراہ ہوں.پس جو شخص ہدایت کی طرف توجہ کرے اسے
ضرور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کے سامان میسر ہوتے ہیں.على هڈی میں جو ھدی پر تنوین ہے یہ تعظیم کے لئے ہے یعنی یہ ہدایت بہت بڑا
مرتبہ رکھتی ہے.وَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ مُفْلِحُون کے معنے حل لغات میں بتائے جاچکے ہیں کہ اپنی
مُراد کو پالینے کے ہوتے ہیں.پس اس جملہ کے یہ معنے ہوئے کہ یہ لوگ اپنی مراد کو پالیتے ہیں
248
Page 257
اور مومن کی مراد اپنے رب کا قرب اور اس سے وصال ہوتا ہے.بعض لوگ اس جگہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ کئی خدا تعالیٰ کے
مقرب اس زندگی میں تکلیفیں اٹھاتے ہیں اور بعض مارے جاتے ہیں تو پھر کیونکر کہا جا سکتا
ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہدایت یافتہ لوگ ضرور کامیاب ہوتے ہیں؟
رض
اس کا جواب یہ ہے کہ مفلح کے معنے اپنی مراد پالینے کے ہیں.نہ کہ دنیوی ترقیات یا جسمانی
راحت کے.اس میں شک نہیں کہ بالعموم خدا تعالیٰ کے مقربوں کو دنیوی کامیابی بھی ہوتی ہے.مگر
وہ ایک ضمنی شے ہے.مقصود نہیں ہے.خدا رسیدہ لوگوں کی مراد تو خدا تعالیٰ کا قرب اور اس کی بھیجی
ہوئی سچائی کی اشاعت ہے.سو اس میں کبھی کوئی خدا رسیدہ ناکام نہیں ہوا.مسیح علیہ السلام کو یہود
ا
نے پھانسی پر تو لٹکا دیا مگر کیا وہ مسیح کے مشن کو نا کام کر سکے؟ اپنے مقصد میں تو مسیح علیہ السلام ہی
کامیاب ہوئے.حضرت امام حسین یزید کے مقابلہ پر شہید ہوئے مگر کیا یزید کا نام بھی اب کوئی لیتا
ہے.جس مقصد کے لئے امام حسین کھڑے ہوئے آخر وہی کامیاب ہوا اور دنیا نے اسلامی نظام
کی اسی تشریح کو قبول کیا جس کے لئے حضرت امام حسین کھڑے ہوئے تھے.یزید کے مقصد کی
تو آج ایک مسلمان بھی تائید نہیں کرتا.مُفلح کے لفظ سے مراد کو پالینے کا وعدہ ہے، نہ یہ کہ وہ اپنے
دشمن کے ہاتھوں ہلاک نہیں ہو سکتے.إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ وَأَنْذَرُتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرُهُمْ لَا
يُؤْمِنُونَ
اس آیت سے یہ مراد نہیں کہ کفار میں سے آئندہ کوئی ایمان نہ لائے گا کیونکہ واقعات اس
امر پر شاہد ہیں کہ اس آیت کے بعد کثرت سے کفار ایمان لائے.بلکہ اس آیت کے بعد
سورۃ نصر نازل ہوئی جس میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسُ
يَدْخُلُونَ فِي دِينِ الله افواجا.یعنی جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص نصرت اور فتح آئے گی
اور تو دیکھے گا کہ لوگ دین الہی میں فوج در فوج داخل ہوں گے.پس جبکہ سورۃ بقرہ کی اس
249
Page 258
آیت کے نزول کے کئی سال بعد قرآن کریم میں فوج در فوج لوگوں کے اسلام میں داخل
ہونے کی خبر دی گئی ہے تو اس آیت کے یہ معنے کسی طرح درست نہیں ہو سکتے کہ اس میں کفار
کے مسلمان نہ ہونے کی خبر دی گئی ہے.یہ شبہ کہ شاید اس آیت میں اس امر کا ذکر ہے کہ آئندہ کوئی کافرایمان نہ لائے گا اس آیت
کے معنوں پر غور نہ کرنے سے پیدا ہوا ہے.ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اس آیت سے
کھینچ تان کر
بھی یہ معنے نہیں نکالے جاسکتے کہ کا فرایمان نہیں لاتے.اس آیت میں تو یہ ذکر ہے کہ جن کفار
کے لئے ڈرانا یا نڈرا نا برابر ہو وہ ایمان نہیں لاتے.اور یہ ظاہر ہے کہ نہ ہر کا فرایسا ہوتا ہے کہ
اس کے لئے ڈرانا یا نہ ڈرا نا برابر ہو اور نہ ہر کا فر ہدایت سے محروم ہوتا ہے.کافرمنکر کا نام ہے اور جب ایسے لوگوں کے سامنے صداقت آئے گی جو اس سے واقف
نہیں اور اس کے دلائل ابھی ان کے ذہن نشین نہیں ہوئے تو وہ اس وقت تک اس کا انکار
کرنے پر مجبور ہوں گے.لیکن ان میں سے ہر شخص وہ نہ ہوگا جو باوجود صداقت کے روشن ہو
جانے کے اس کا منکر ہوگا اور نہ ہر شخص ایسا ہو گا جس کی دماغی قابلیت کے لحاظ سے پہلے ہی دن
اس پر صداقت روشن ہو سکے گی.پس ہر ایسا شخص اس آیت کے مصداقوں میں سے نہ ہوگا.اس کا مصداق وہی ہو گا جو باوجود صداقت کھل جانے کے اس کا انکار کرے گا یا اس کوشش
میں لگا رہے گا کہ مجھ پر صداقت کھلے ہی نہ.اور ظاہر ہے کہ ان دونوں صفات والالم
والا شخص جب
تک اپنی اس حالت کو نہ بدلے ایمان نہیں لا سکتا.خَتَمَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ
عَذَابٌ عَظِيمٌ
خَتَمَ اللهُ عَلى قَلبہ جب بولا جائے تو اس کے یہ معنے ہوں گے کہ اس کے دل کو ایسا بنا دیا
کہ وہ کوئی بات نہیں سمجھ سکتا اور نہ اپنی بات سمجھا سکتا ہے.( کلیات ابی البقاء)
خَتَمَ الله عَلى قُلُو مہم میں ختم کا لفظ بولنے سے اللہ تعالیٰ کے اس قانون کی طرف اشارہ
250
Page 259
ہے کہ جب انسان اعتقاد باطل یا ممنوع باتوں کے ارتکاب میں حد سے بڑھ جاتا ہے اور حق کی
طرف کسی طرح بھی تو جہ نہیں کرتا تو اس کا یہ طرز عمل اس کے اندر ایک ایسی حالت پیدا کر دیتا
ہے جو گناہوں کے ارتکاب کو عمدہ بجھتی ہے گویا اس کے دل پر اب مہر لگ گئی کہ نہ اس پر حق کا
اثر ہوتا ہے اور نہ اس کا دل حق کی طرف رجوع کرتا ہے ( مفردات )
قُلُوب قلب کی جمع ہے اور اس کے معنے ہیں الْفُؤَادُ - دل - وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى الْعَقْلِ
اور
کبھی قلب کا لفظ عقل پر بھی بولا جاتا ہے (اقرب)
اور لفظ قلب کے ذریعہ ان کیفیات کو بیان کیا جاتا ہے جو روح علم اور شجاعت وغیرہ اقسام
کی اس کے ساتھ مخصوص ہیں.السيعُ : مفردات میں ہے السَّمْعُ قُوَةٌ فِي الْأُذُنِ بِهِ يُدْرَكُ الْأَصْوَاتُ یعنی سمع کان کی
ایک قوت ( شنوائی) کا نام ہے جس کے ذریعہ سے انسان آواز کو معلوم کرتا ہے.وَفِعْلُهُ
يُقال له الشمعُ أيضًا.اور سننے کے فعل کا نام بھی سمع رکھا جاتا ہے وَيُعَبرُ تَارَةٌ بِالسَّمْعِ عَنِ
الْأُذُنِ اور کبھی لفظ سمع بول کر کان مراد ہوتا ہے.وَتَارَةً عَنْ فِعْلِهِ كَأَسْمَاعِ اور کبھی لفظ سمع سے
اس کا فعل مرا دلیا جاتا ہے.عذاب کے معنے ہیں ہر وہ چیز جو انسان پر شاق گذرے اور حصول مراد سے اُسے روک
دے.عَذَاب کے معنے ہیں (1) تکلیف (2) ایسی چیز جوزندگی کی حلاوت سے محروم کر دے
(3) جو مقصود حیات سے محروم کر دے.اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تین لطیف باتوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے اور توجہ دلائی
ہے کہ اگر غور کرو تو عنادی کا فروہی ہوتے ہیں جو دل ، کان اور آنکھوں سے کام لینا چھوڑ دیتے
ہیں.اور ہدایت کے یہی تین بڑے ذریعے ہیں اور ہر ایک بات پر غورا نہی تین طریق سے ہو
سکتا ہے.اول دل ہے.سب سے پہلا ہدایت کا ذریعہ یہی ہے.جو شخص سوچنے کا عادی ہوتا
ہے وہ بیسیوں صداقتوں کو پالیتا ہے.دوم کان ہیں.اگر کسی میں زیادہ عقل اور سمجھ نہیں ہوتی کہ
251
Page 260
غور کر کے خود فیصلہ کر لے.وہ کسی سے سن کر بات مان لیتا ہے.تیسرے آنکھیں ہیں.اگر
کانوں سے سن کر ہدایت نہ پائے تو کم سے کم آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے کہ جو باتیں مجھ سے کہی
جاتی ہیں اُن کا نتیجہ دنیا میں کیا پیدا ہورہا ہے.اگر نتیجہ اچھا نکل رہا ہوتو وہ معلوم کر سکتا ہے کہ گو
کانوں سے سن کر وہ باتیں بھلی معلوم نہیں ہوتیں مگر مشاہدہ نے ان کی تصدیق کر دی ہے.لیکن
جو بد بخت ان تینوں باتوں سے عاری ہو وہ کبھی کوئی بات نہیں مان سکتا.وہ ہمیشہ دکھ اٹھاتا
ہے.پس وہ انسان جو دنیا کی اشیاء پر غور کر کے خود صحیح نتیجہ پر نہیں پہنچ سکتا وہ اگر انبیاء کے منہ
سے نکلی ہوئی باتیں سنے تو اسے ہدایت مل سکتی ہے.اگر ان کو سن کر اس کا دل فیصلہ نہ کر سکے تو وہ
خدا تعالیٰ کی قدرت کے جلوے اور نظارے دیکھ کر مان سکتا ہے کہ وہ کس کی تائید میں ہیں.اور
اگر وہ نہ خود سوچے اور نہ علم کی باتوں کو سنے اور نہ خدا تعالیٰ کے نشانات کو دیکھے تو اس کا انجام اس
کے سوا کیا ہوگا کہ وہ دکھوں میں پڑ جائے.اس آیت کا یہ مطلب نہیں جیسا کہ مخالفین اسلام نے اس سے نتیجہ نکالا ہے کہ خدا تعالیٰ
جبر اکفار کے دلوں پر اور کانوں پر مہر لگا دیتا ہے اور ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیتا ہے.یہ تو ظلم ہے اور قرآن کریم خدا تعالیٰ سے ظلم کی نفی فرماتا ہے.دوسرے اگر ان معنوں کو تسلیم کیا جائے تو ثابت ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ خود بعض بندوں کے
لئے کفر کو پسند کرتا ہے.حالانکہ قرآن کریم میں ہے وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ (الزمر 8) کہ
اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لئے کفر کو نا پسند کرتا ہے.تیسرے ان معنوں سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جبر سے بعض لوگوں سے کفر کرواتا ہے.لیکن قرآن کریم اس مضمون کو بھی رد کرتا ہے.چنانچہ فرماتا ہے فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْ مِنْ وَمَنْ شَاءَ
فَلْيَكْفُرُ (کھف (30) یعنی جو چاہے اللہ کی طرف سے نازل شدہ کلام پر ایمان لے آئے اور جو
چاہیے اس کا انکار کر دے.اصل بات یہ ہے کہ جیسا کہ قرآن کریم سے ثابت ہے یہ مہر اور پردہ انسان کے اپنے ہی
252
Page 261
اعمال کا نتیجہ ہے.جیسے فرما یا طَبَعَ اللهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمُ (نساء (156) کہ اللہ نے اُن کے
کفر کی وجہ سے اُن کے دلوں پر مہر کر دی ہے.اگر کہا جائے کہ پھر کیا وجہ کہ اس آیت میں مہر لگانے کی نسبت خدا تعالیٰ کی طرف کی گئی
ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ انسان کے اعمال کا یہ نتیجہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ظاہر
ہوتا ہے اس لئے ان آیات میں ختم اور طبع کی نسبت جناب الہی کی طرف کی گئی ہے.ور نہ ایک دوسری آیت میں اس مہر کو خود کفار کی طرف منسوب کیا گیا ہے.چنانچہ فرماتا ہے
أَفَلَا يَتَد برُونَ الْقُرْآنَ آمَ عَلَى قُلُوبِ أَقْفَالُهَا (محمد (25) یعنی کیا کفار قرآن کریم کے
مضمون پر غور نہیں کرتے؟ یا یہ بات ہے کہ ان کے دلوں پر انہی کے دلوں سے پیدا شدہ قفل
لگے ہوئے ہیں؟
اس جگہ یہ بھی یادر ہے کہ مہر اور پردہ کوئی جسمانی چیز نہیں ہیں.پر دہ اور ختم وغیرہ کے الفاظ
بطور استعارہ ہیں.وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِیم میں جس بڑے عذاب کی خبر دی گئی ہے اس سے صرف بعد الموت
کی جہنم کی سزا ہی مراد نہیں بلکہ سب سے زیادہ اس میں خدا تعالیٰ کی دوری کا ذکر ہے.اس آیت کے بارہ میں ایک سوال یہ بھی ہوسکتا ہے کہ دل اور آنکھوں کو تو جمع بیان کیا
اور کانوں کے لئے مفرد کا لفظ رکھا ہے اس میں کیا حکمت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دلوں اور
آنکھوں کا فعل ہر شخص کا جدا گانہ ہوتا ہے.دلوں کی طاقتوں کا اس قدر فرق ہوتا ہے کہ کوئی
تحت الثریٰ میں ہوتا ہے اور کوئی افلاک پر.اسی طرح آنکھوں کے فعل سے اس جگہ معجزات
اور نشانوں کو دیکھنا مراد ہے.اس کا اندازہ بھی ہر شخص الگ الگ لگا تا ہے.اور اس طرح گویا
مختلف آنکھوں سے ان کو دیکھا جاتا ہے مگرسنی جانے والی شئے ایک معین چیز ہے یعنی
قرآن کریم.وہ معین الفاظ میں سب کے سامنے پڑھا جا تا تھا.پس سوچنے میں گوسب مختلف
تھے اور معجزات کا نظارہ کرنے میں بھی مختلف تھے مگر سننے میں مختلف نہ تھے کیونکہ ایک ہی کلام
253
Page 262
سنتے تھے.پس سننے کے لئے مفرد کا لفظ استعمال کیا کہ گویا سب ایک ہی کان سے سنتے تھے.ایک سوال اس آیت کے بارہ میں یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ دلوں اور کان کے لئے تو مہر کا لفظ
استعمال کیا گیا ہے جو زیادہ سخت ہے لیکن آنکھوں کے لئے پردہ کا لفظ استعمال کیا ہے جو ہٹ بھی
سکتا ہے لیکن سورۃ نحل رکوع 14 میں فرماتا ہے طَبَعَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَ
أَبْصَارِهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُون یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں، ان کے کان اور ان کی
آنکھوں پر مہر لگادی ہے.اس اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ پہلے انسان اپنے دل میں غور کرتا ہے پھر
بات سن کر ہدایت پاتا ہے اور جب یہ بھی نہ ہو تو معجزات کو دیکھتا ہے.معجزات کلام کے بعد آہستہ
آہستہ ظاہر ہوتے ہیں اس لئے آنکھوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیر میں مہر لگائی جاتی ہے کیونکہ
اس راستہ کے ذریعہ حجت دیر سے قائم ہوتی ہے.پہلے پردے پڑتے ہیں پھر مہر لگتی ہے.پس
سورۃ بقرہ میں اس حالت کا ذکر ہے کہ جب ابھی مہر کا وقت نہ آیا تھا اور سورۃ نحل میں اس حالت کا
ذکر ہے جبکہ معجزات کو دیکھ کر بھی ایک لمبے عرصہ تک انسان ایمان نہ لائے.حمد اس جگہ یہ لطیفہ بھی یادرکھنے کے قابل ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قلوب اور
کانوں پر مہر لگانے کو تو اپنی طرف منسوب کیا ہے لیکن آنکھوں کے پردوں کو اپنی طرف
منسوب نہیں کیا.اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ کفار یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے ہمیں سمجھ
نہیں دی کہ ہم اس کی بار یک حکمتوں کو سمجھ سکیں اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں سنے کا موقعہ نہیں
ملا.گوحق یہ ہے کہ انہوں نے خود ہی نہیں سنا.لیکن وہ اس بات کا کیا جواب دیں گے کہ خدا
تعالی کی تائیدات اور نصرتیں ان کے دائیں اور بائیں اور سامنے ظاہر ہورہی ہیں.انہیں انہوں
نے کیوں نہیں دیکھا.پس اس مضمون کو واضح کر دیا ہے کہ ختم کا خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کیا
جانا صرف نتیجہ فعل کے طور پر ہے ورنہ یہ دونوں نتائج بھی خود کفار کے اعمال کی وجہ سے پیدا
ہوئے ہیں.جس طرح ان کا نشانات کو نہ دیکھنا ان کا اپنا فعل ہے.254
Page 263
وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ
مُؤْمِنين.هُدًى لِلْمُتَّقِينَ سے هُمُ الْمُفْلِحُونَ تک اس گروہ کا ذکر کیا جو ایمان پر مستقل طور پر قائم
ہے اور اس کے ایمان سے جو فوائد وابستہ ہیں ان سے پوری طرح فائدہ اٹھاتا ہے.پھر ان
الَّذِينَ كَفَرُوا سے اس گروہ کا ذکر کیا جو کفر و عصیان سے مستقل طور پر وابستہ ہے اور اس کے
بد نتائج کا مستحق ہو چکا ہے.انہی کے ذکر میں ضمناً ان کفار کا بھی ذکر آ گیا جو گوعقیدۃ کافر ہیں
لیکن ان کے دلوں میں تعصب نہیں.وہ صداقت کے سمجھ آ جانے پر اسے قبول کرنے کے لئے
بھی تیار ہیں اور اس کے سمجھنے کے لئے بھی کوشش کرتے ہیں کیونکہ جب یہ فرمایا کہ وہ کافر
ایمان نہیں لائیں گے جنہوں نے سُنا آن سُنا کر چھوڑا ہے اور جو اس حد تک متعصب ہیں کہ سچائی
کو قبول نہ کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں تو اس سے ضمنا یہ نتیجہ بھی نکل آیا کہ جو کافر سنتے ہیں اور سچائی
کو اگر سمجھ میں آ جائے ماننے پر آمادہ ہیں وہ جیسے جیسے انکشاف تام ان پر ہوتا جائے گا ایمان
لاتے چلے جائیں گے.اب اس آیت سے قرآن کریم سے تعلق رکھنے والے ایک اور گروہ کا ذکر کرتا ہے جو
منافقوں کا گروہ کہلاتا ہے.مومنوں کی جماعت کو مدنظر رکھتے ہوئے منافق دو قسم کے ہوتے
ہیں.ایک وہ جو صرف ظاہر میں مومنوں سے ملے ہوئے ہوتے ہیں لیکن دل میں منکر ہوتے
ہیں اور ان کی ظاہری شمولیت محض دنیوی فوائد یا قومی جتھا بندی کی وجہ سے ہوتی ہے.اور
ایک وہ منافق جو عقلی دلائل سے تو ایمان کے اصول کو تسلیم کرتے ہیں لیکن اُن کے اندر ایسی
مضبوطی نہیں ہوتی کہ اس کے لئے پوری طرح قربانیاں کر سکیں.پس ایسے لوگ اپنی عملی
کمزوری کی وجہ سے ، نہ کہ عقیدہ کے اختلاف کی وجہ سے عمل میں سستی دکھاتے ہیں اور کبھی
کفار کا زیادہ دباؤ پڑے تو ان کی ہاں میں ہاں بھی ملا دیتے ہیں اور اُن سے تعلق و محبت بھی جتا
دیتے ہیں اور دل میں خیال کرتے ہیں کہ جب صداقت کو اللہ تعالیٰ نے غلبہ دینا ہی ہے تو کیا
255
Page 264
حرج ہے کہ مداہنت کر کے ہم اپنے آپ کو نقصان سے بچالیں.اور یہ نہیں سمجھتے کہ اگر سب
لوگ ہی اس طریق کو اختیار کرلیں تو صداقت کی تائید کون کرے.اور یہ خیال بھی نہیں کرتے
که صداقت کو تو بے شک اللہ تعالی نے فتح دینی ہی ہے لیکن انہیں اپنے انجام کا بھی تو خیال
کرنا چاہئے.اگر صداقت کامیاب ہو گئی مگر وہ صداقت کے منکروں میں شامل ہو گئے تو ان کو
اس سے کیا فائدہ.آیت زیر تفسیر میں اس تیسرے گروہ کے پہلے حصہ کا یعنی جو دل سے قرآن کریم کے منکر
تھے لیکن ظاہر میں مسلمانوں میں شامل تھے ذکر کیا گیا ہے.فرماتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ
ظاہر میں تو وہ مسلمانوں میں شامل ہیں لیکن اُن کے دل میں اسلام کی صداقتوں پر پورا یقین
نہیں.وہ منہ سے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور یوم آخر کو مانتے ہیں لیکن اُن کے دلوں میں اللہ اور
یوم آخر پر کوئی ایمان نہیں.اس آیت میں صرف اللہ اور یوم آخر پر ایمان کا ذکر ہے.کلام الہی یا انبیاء وغیرہ کا ذکر
نہیں.اس کی یہ وجہ ہے کہ ایمانیات کے سلسلہ کی پہلی کڑی خدا تعالی پر ایمان لانا ہے اور
آخری کڑی یوم آخر پر ایمان لانا.پس اختصار کے لئے صرف پہلی اور آخری کڑی کا ذکر کر
دیا گیا اور درمیانی امور کو چھوڑ دیا گیا کیونکہ ابتدا اور انتہا کے ذکر سے درمیانی اُمور خود ہی سمجھ آ
جاتے ہیں.پس گو کفار کا قول اختصار ا یہی نقل کیا ہے کہ ہم اللہ اور یوم آخر پر ایمان لاتے
ہیں لیکن مراد یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے لے کر یوم آخر تک سب امور ایمانیہ کو مانتے
ہیں جیسے کہ ہماری زبان میں بھی کہہ دیتے ہیں کہ الف سے یا تک سب بات سمجھ لی ہے.اس آیت کو ومن الناس سے شروع کرنے میں یہ حکمت بھی ہے کہ منافقوں کو ان
کی انسانیت کی طرف توجہ دلائی جائے.کیونکہ قرآن کریم میں جہاں جہاں بھی کاش کا لفظ
استعمال ہوا ہے بشر کی اچھی قوتوں اور استعدادوں کی طرف اشارہ کرنے کے لئے استعمال ہوا
ہے.ورنہ یا تو قرآن کریم کفار کا لفظ استعمال کر کے یا صرف ضمیر کے استعمال سے یا ملکوں یا
256
Page 265
قوموں کا نام بیان کر کے مخالفین صداقت کا ذکر کرتا ہے.پس اس جگہ ومن الناس کہہ کر
ایک لطیف طنز سے انہیں نیکی کی طرف توجہ دلائی ہے کہ انسان اور حیوان میں یہی فرق ہے کہ
حیوان ایک مقرر راستہ پر چلتا جاتا ہے اور انسان سمجھ کر کام کرتا ہے.سوانسانیت کے جامعہ کی تم
کو اس قدر تو عزت ہونی چاہئے تھی کہ جس امر کو سچا سمجھتے تھے اس پر کار بند ہوتے.اور اگر
تمہاری قوم مسلمان ہو بھی گئی تھی لیکن تم خود اسلام کو برا سمجھتے تھے تو بھیڑوں کی طرح ان کے پیچھے
نہ چلتے بلکہ جو تمہارا عقیدہ خلاف اسلام تھا اس پر قائم رہتے.وَمَا هُمْ مُؤْمِنین کہہ کر اس بات پر زور دیا ہے کہ ان کے اندر کوئی شائبہ بھی ایمان کا
نہیں.ما سے نفی کر کے پھر بعد میں باء کا استعمال عربی میں زور پیدا کرنے کے لئے ہوتا ہے
اور اُردو میں اس کا صحیح ترجمہ ہر گز کی زیادتی سے ہوتا ہے.یعنی اس جملہ کا یہ ترجمہ نہیں کہ وہ
مومن نہیں بلکہ یہ ہے کہ وہ ہر گز مومن نہیں.اگر صرف عدم ایمان کا اظہار کرنا ہوتا تو اس
مضمون کو دوسری ترکیب سے بیان کیا جاتا.مندرجہ بالا آیات اور آیت زیر تفسیر میں ان لوگوں کے خیالات کی زبر دست تردید
ہوتی ہے کہ جو کہتے ہیں کہ اسلام نے لوگوں کو زبردستی مسلمان کرنے کا حکم دیا ہے.اس غلطی
میں بعض مسلمان بھی پھنسے ہوئے ہیں اور دشمنانِ اسلام نے تو اس غلط عقیدہ کو اسلام کی طرف
منسوب کر کے اس پر اعتراض کرنا ایک مشغلہ بنا رکھا ہے حالانکہ اگر یہ دھوکا خوردہ مسلمان اور
وہ دشمنانِ اسلام اسی آیت پر غور کرتے تو انہیں معلوم ہوتا کہ اسلام جبر کے سراسر خلاف ہے
کیونکہ جبر منافقت پیدا کرتا ہے اور جبر کسی کو مسلمان بنانے کے یہی معنے ہیں کہ گو تیرا دل
اور دماغ اسلام پر تسلی نہیں پاتا لیکن تو ظاہر میں کہہ دے کہ میں مسلمان ہوں.اب ظاہر ہے
کہ جو مذہب ایسی مذہبی تبدیلی کو جائز بلکہ پسند کرے گا وہ لازما منافق کو اپنی جماعت کا جزو
سمجھے گا اور اُسے کبھی خارج نہیں کر سکتا.لیکن قرآن کریم تو جیسا کہ اوپر کی آیات میں بتایا گیا
ہے سختی سے ایسے لوگوں کو ملامت کرتا ہے اور ان کی نسبت اعلان کرتا ہے کہ وہ مومن نہیں
257
Page 266
ہیں.اور یہ امر ظاہر ہے کہ جو مذہب منافقوں کو اپنے اندر شامل کرنے کے لئے تیار نہیں اور
صرف دل کی تسلی کے بعد درست عقیدہ رکھنے والے کو اپنا جز و قرار دیتا ہے وہ زبردستی اور تلوار
سے کسی شخص کو نہ اپنے اندر شامل کر سکتا ہے، نہ اسے جائز قراردے سکتا ہے.يُخَادِعُونَ اللهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا
يَشْعُرُونَ
يُخادِعُونَ کے مختلف لغوی معنوں کے پیش نظر يُخادِعُونَ اللہ کے معنے یہ ہوں گے
که (1) وہ اللہ کو دھوکا دینا چاہتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ دھوکا نہیں کھاتا.(2) جو اُن کے دلوں
میں بات ہے اس کے خلاف اظہار کر کے شک میں ڈالنا چاہتے ہیں ( 3 ) وہ خدا کے دین
کے معاملہ میں فساد کرتے ہیں (4) وہ اللہ کو روکتے ہیں یعنی دین کی اشاعت میں روکیں
ڈالتے ہیں.اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایمان وہی کار آمد ہوتا ہے جو نیک نیتی اور اخلاص اور
صداقت پر مبنی ہو.جس ایمان میں اخلاص نہیں وہ کسی کام کا نہیں کیونکہ وہ تو دھوکا ہے اور
خدا تعالیٰ جو عالم الغیب ہے وہ دھوکا کب کھا سکتا ہے.خلاصہ یہ کہ يُخادِعُونَ اللہ کے معنے اس جگہ یہ ہیں کہ (1) وہ خدا تعالیٰ سے ایسا معاملہ
کرتے ہیں جو دھو کے کے مشابہ ہے (2) وہ خدا تعالیٰ کو دھوکا دینا چاہتے ہیں حالانکہ وہ دھوکا
میں نہیں آسکتا (3) وہ خدا تعالیٰ سے دھو کے کا معاملہ کرتے ہیں اس لئے خدا تعالیٰ اُن کے
غیر مخلصانہ افعال کی سزا دے گا.(4) وہ خدا تعالیٰ کو چھوڑ رہے ہیں.(5) منافقوں کا معاملہ
خدا تعالیٰ سے اخلاص کا نہیں ہے.کبھی وہ مومنوں کے رعب میں آ کر اچھے کام کرنے لگ
جاتے ہیں اور کبھی کفار کے اثر کے نیچے دین کی مخالفت شروع کر دیتے ہیں.(6) ایک معنے
خداع کے فساد کے بھی ہیں.ان معنوں کے رو سے اس کے یہ معنے ہوں گے کہ وہ خدا تعالیٰ
سے فساد کا معاملہ کرتے ہیں یعنی ان کے کاموں میں اخلاص نہیں ہے.(7) ایک معنے اس
258
Page 267
کے یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دھوکا کرنے سے مراد یہ ہو کہ وہ خدا تعالیٰ کے رسول اور
مومنوں سے دھو کے کا معاملہ کرتے ہیں.وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ میں اس حقیقت کو ظاہر کیا گیا ہے کہ منافقوں کے
غیر مخلصانہ افعال خود ان کے لئے وبال بن جائیں گے.کیونکہ جو شخص دھوکے سے کام لیتا ہے
آخر اس کا وبال اسی پر پڑتا ہے اور وہ دنیا اور آخرت میں ذلیل ہوتا ہے.پس جبکہ وہ سمجھ رہا ہوتا
ہے کہ میں دوسروں کو دھوکا دے رہا ہوں وہ در حقیقت اپنے نفس کو دھوکا دے رہا ہوتا ہے اور
خود اپنی تباہی کے سامان کر رہا ہوتا ہے.وَمَا يَشْعُرُونَ اور وہ سمجھتے نہیں.شعور کے معنے بار یک امور کے جاننے کے ہوتے
ہیں.قرآن کریم میں اس کے مشابہ الفاظ علم ، عرفان، عقل اور فکر کے استعمال ہوئے ہیں.بظاہر
ید الفاظ مشابہ ہیں لیکن ان سب الفاظ کے معانی ایک دوسرے سے مختلف ہیں.چنانچہ علم اس قسم
کے جاننے کے لئے آتا ہے جو باہر سے پیدا ہو.یعنی سن کر یا دیکھ کر یا مچھو کر یا چکھ کر پیدا
ہو.اسی طرح عرفان اس علم کو کہتے ہیں جو دوبارہ حاصل ہو کیونکہ عرفان پہچاننے کو کہتے ہیں اور
پہچانتا انسان اُس شے کو ہے جس کا علم اسے پہلے حاصل ہو چکا ہو.عقل اس قوت کو کہتے ہیں کہ
جو انسان کو علم ، فکر اور شعور کے مطابق کام کرنے کی توفیق بخشتی ہے اور عاقل وہ ہے جو علم صحیح ،
فکر صحیح اور شعور صحیح کے مطابق کام کرے اور اپنے نفس کو ان کے خلاف چلنے سے روکے.فکر
اس قوت کا نام ہے جو بیرونی علم سے نتائج اخذ کرنے میں مدد دیتی ہے.اور شعور اس حس کو
کہتے ہیں جو اندر سے پیدا ہوتی ہے اور فطرت صحیحہ کو معلوم کرنے کا نام ہے.پس وَمَا يَشْعُرُونَ کے یہ معنے ہوئے کہ دھوکا دینا ایک ایسا فعل ہے جس کے خلاف
فطرت صحیحہ گواہی دیتی ہے مگر یہ لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے مذہب کو تو کیا سمجھنا ہے خود اپنے
نفس کو بھی نہیں سمجھتے اور نہیں جانتے کہ منافقت ان افعال قبیحہ میں سے ہے کہ جن کو فطرت
صحیحہ بھی رڈ کرتی ہے اور کسی دوسرے شخص کے بتانے کی بھی ضرورت نہیں.259
Page 268
فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللهُ مَرَضًا - وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا
كَانُوا يَكْذِبُونَ
مرضٌ : مفردات میں مرض کے معنے یہ کئے گئے ہیں کہ ہر وہ چیز جو انسان کو صحت کی حد
سے باہر نکال دے.اور اس کی دو اقسام ہیں.اول جسمانی مرض.دوسرے جملہ بری عادات
جیسے جہالت، بزدلی، بخل، نفاق وغیرہ.اس آیت میں بیماری سے مراد نفاق کی بیماری ہے.پہلے رکوع کے شروع میں روحانی
طور پر تندرست لوگوں کا ذکر تھا.پھر کفر کے بیماروں کا ذکر ہوا.اب اس آیت میں نفاق کی
بیماری کا ذکر کیا گیا ہے.نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفاق کی بیماری کی مندرجہ ذیل علامات بتائی ہیں اذا
حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ (بخاری
كتاب المظالم و كتاب الشهادات) یعنی جب منافق بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے اور
جب وعدہ کرتا ہے تو پورا نہیں کرتا اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھا ئیں تو وہ خیانت کرتا
ہے اور جب معاہدہ کرے تو اسے توڑ دیتا ہے اور جب جھگڑا ہو تو گالیوں پر اتر آتا ہے.یہ علامات منافقت کا لازمہ ہیں.کیونکہ منافق چونکہ اپنے نفاق کو چھپانا چاہتا ہے اس کا
ذریعہ وہ یہی سمجھتا ہے کہ اگر اس پر کوئی الزام لگائے اور اس کے عیب کو ظاہر کرے تو وُہ
جھوٹ بولے اور اس سے لڑ پڑے اور گالیوں پر اتر آئے تا کہ لوگوں کی توجہ دوسری طرف پھر
جائے.اسی طرح اُسے جھوٹ بولنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ اس کے بغیر وہ اپنے
اندر رونہ کو چھپا نہیں سکتا.وعدہ خلافی اور عہد کو توڑنا بھی اس کے خواص میں ہونا لازمی ہے
کیونکہ منافق وہی ہوتا ہے جو ایک قوم سے بظاہر تعلق رکھ کر دراصل اس سے بگاڑ رکھے.امانت میں خیانت بھی اس کا ضروری خاصہ ہوتا ہے کیونکہ اپنے قومی را ز غیروں کو بتائے بغیر وہ
ان میں مقبول نہیں ہوسکتا.260
Page 269
م اس آیت میں بیماری کا بڑھانا اللہ تعالیٰ کی طرف اس لئے منسوب کیا گیا ہے کہ یہ اُسی
کے احکام اور قوانین کی خلاف ورزی کا نتیجہ ہے اور لوگوں کے اعمال پر نیک و بد نتائج بھی وہی
مرتب فرماتا ہے.ورنہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو کسی کی بیماری کے بڑھانے کے لئے
نازل نہیں فرمایا بلکہ لوگوں کی بیماری کے دور کرنے کے لئے بھیجا ہے.چنانچہ فرماتا ہے
يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَ تُكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَّبِّكُمْ وَشِفَا لِمَا فِي الصُّدُورِ (يونس (58) یعنی
اے لوگو تمہارے پاس ایک ایسی کتاب آئی ہے جو دل پر اثر کرنے والی نصائح پر مشتمل ہے
اور سینہ کی سب بیماریوں کے لئے شفا ہے.یہ مرض جس کا اس آیت میں ذکر ہے قوت فیصلہ کا نہ ہونا، بزدلی اور نفاق ہے جیسا کہ اللہ
تعالیٰ دوسری جگہ قرآن شریف میں فرماتا ہے فَاعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ
يما اخْلَفُوا اللهَ مَا وَعَدُوهُ وَ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ (توبه (77) یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی وعدہ
خلافی اور جھوٹ کا یہ انجام دکھایا کہ اُن کے دلوں میں نفاق پیدا ہو گیا.(2) اللہ تعالیٰ کے مرض بڑھا دینے سے ایک یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ جوں جوں مسلمانوں
کو ترقی دیتا اور اُن کی طاقت بڑھاتا گیا منافقوں کو اپنے دلی عقیدے کے خلاف ان کے
ساتھ تعلقات قائم رکھنے کی وجہ سے اور زیادہ نفاق سے کام لینا پڑا.دوسرے شریعت اسلامی
آہستہ آہستہ نازل ہوئی پس جوں جوں احکام اور مسائل بڑھتے گئے منافقوں کا نفاق بھی بڑھتا
جاتا تھا اور ان کی گھبراہٹ اور بزدلی میں اضافہ ہوتا جاتا تھا.پہلی آیات میں کفار کی نسبت فرمایا تھا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ان کے لئے بڑا عذاب
ہے.اس آیت میں منافقوں کی نسبت فرمایا ہے کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ یعنی اُن کے لئے
درد ناک عذاب ہے.اس فرق کی وجہ یہ ہے کہ کافر کو خواہ کس قدر عذاب ملتا ہو وہ مقابلہ کر
کے اپنے دل کا بخار نکال لیتا ہے اور اس طرح بدلہ لینے سے جو انسان کو تسلی ہوتی ہے وہ اسے
حاصل ہو جاتی ہے.مگر منافق بد بخت چونکہ اپنے اندرونہ کو چھپاتا ہے اندر ہی اندر کڑھ کڑھ کر
261
Page 270
مرتا ہے.اس لئے منافق کی اس حالت کی طرف اشارہ کرنے کے لئے عَذَاب الیم کے
الفاظ استعمال کئے گئے کہ اُسے دُکھ کے ساتھ جلن کا مزہ بھی چکھنا پڑتا ہے.وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ
منافقوں کا فساد کئی رنگ میں ظاہر ہوتا تھا (1) وہ مہاجرین اور انصار میں فساد
ڈلوانے کی کوشش کرتے رہتے تھے اور قومی سوال کو اپنے بد اغراض کو پورا کرنے کے لئے
آڑ بناتے رہتے تھے.کبھی یہ لوگ قومی گنہگاروں کی پیٹھ ٹھونکتے تھے کہ تا وہ جوش میں آ کر اسلام سے برگشتہ ہو
جائیں.کبھی رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم کے اعمال پر معترض ہوتے تا کہ لوگوں میں بددلی
پھیلائیں.جیسا کہ قرآن کریم میں آتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَتِ (توبه 58) یعنی
ان
منافقوں میں سے وہ بھی ہیں جو تیری صدقات کی تقسیم پر معترض ہوتے ہیں.اس سے ان کی
غرض یہ ہوتی تھی کہ جن کو صدقہ میں سے مال نہ ملا ہو ان میں بد دلی پیدا ہو.اسی طرح آپ کے
متعلق اعتراض کرتے کہ هُوَ أُذُن (توبه (61) وہ تو کان ہی کان ہے یعنی اس نے تو چاروں
طرف جاسوس چھوڑ رکھے ہوئے ہیں.کوئی آدمی آزادی سے اپنے خیالات ظاہر نہیں کرسکتا.کبھی مشکلات کے وقت مسلمانوں میں بددلی پیدا کرنے کی کوشش کرتے.جیسا کہ فرماتا
ہے.وَإِن تُصِبكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا امْرَنَا مِن قَبْلُ (توبه 50) یعنی اگر رسول کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مخلصین صحابہ کو کوئی نقصان جنگ میں پہنچتا تو کہتے کہ دیکھا یہ ہمارے
مشورہ پر عمل نہ کرنے کا نتیجہ ہے.ہم نے پہلے ہی صورتِ حالات کو بھانپ لیا تھا اور اس
جنگ میں شامل نہ ہوئے تھے.کبھی کفار کو مسلمانوں کے خلاف جوش دلاتے.اسی طرح ایک فساد کا طریق یہ تھا کہ وہ مسلمانوں کو ڈرانے کی کوشش کرتے تھے.غرض منافق طرح طرح سے ملک میں فساد پیدا کرتے تھے اور اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ
جب ان سے کہا جاتا کہ اس طرح فساد پیدا کرنے سے کیا فائدہ.ایسا نہ کرو.تو وہ یہ جواب دیتے کہ
262
Page 271
ہم تو صرف اصلاح کے خاطر یہ سب کام کرتے ہیں.یہ بھی منافقوں کی ایک علامت ہے کہ اپنے
گندے اعمال کو چھپانے کے لئے ہمیشہ اپنے اعمال کے لئے کوئی نہ کوئی ایسا بہانہ بنا لیتے ہیں کہ
جس سے ان کے اعمال بظاہر نیک نظر آئیں.کسی موقعہ پر غریبوں کی امداد کا بہانہ.کسی موقعہ پر
مسلمانوں کو تباہی سے بچانے کا بہانہ.غرض اپنی بدنیتی کو نیک نیتی کے پردہ میں چھپانے کی
کوشش ہمیشہ ان کی طرف سے ہوتی رہتی ہے.اور اگر وہ یہ نہ کریں تو اپنے نفاق کو چھپائیں کس
طرح.ہر قوم اور ہر ملک کے منافق اسی طرح کرتے ہیں.اور جن قوموں کی تباہی کے دن آ جاتے
ہیں وہ ان کے دھوکے میں آکر بچے خیر خواہوں کو چھوڑ دیتی ہیں.مگر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو ان کے
دھوکے سے بچایا اور ان کی شرارتیں انہی کے سروں پر الٹ پڑیں.منظم جماعتوں میں منافقوں کا گروہ ضروری ہوتا ہے.کیونکہ جب تنظیم نہ ہو تو منافقت
کرنے کی ضرورت کم ہی ہوتی ہے لیکن جب ایک جماعت منظم ہو تو اسے چھوڑ نا کمزور دل
لوگوں کے لئے مشکل ہو جاتا ہے.اس لئے وہ ایک طرف تو اپنی جماعت سے بھی تعلق بنائے
رکھتے ہیں اور دوسری طرف خفیہ خفیہ اس کے مخالفوں سے بھی ساز باز شروع کر دیتے ہیں.جماعت احمد یہ چونکہ ایک منظم جماعت ہے اسے اس خطرہ کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہئے.منافقوں کا وجود اس میں پایا جانا اس کی کمزوری کی علامت نہیں بلکہ اس
کی تنظیم کا ثبوت ہے.ہاں ضرورت اس امر کی ہے کہ وہ منافقوں کی چالوں کو جو قرآن کریم میں بیان ہوئی ہیں سمجھے اور
انہیں مد نظر رکھ کر منافقوں کو پہچانے اور ان سے وہی معاملہ کرے جو قرآن کریم نے تجویز کیا
اور ان کے ہتھکنڈوں میں نہ آئے کہ وہ شیطان کی طرح خیر خواہ بن کر ہی حملے کیا کرتے ہیں.الا انهم هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُرُونَ
پہلے ثابت کیا جا چکا ہے کہ منافق قسم قسم کے فساد کرتے تھے مگر اپنے مفسدانہ اعمال کی
کوئی نہ کوئی نیک توجیہ پیش کر دیا کرتے تھے.لیکن نیک توجیہ بُرے کام کو اچھا نہیں بنا
دیتی.اگر کوئی شخص کسی جماعت کے نظام یا عقیدہ سے خوش نہ ہو تو اس کا فرض ہوتا ہے کہ اس
263
Page 272
سے جدا ہو جائے ، نہ کہ اس میں رہ کر اس میں فساد پیدا کرنے کی کوشش کرے.اس آیت کے آخر میں منافقوں کے اندر شعور کی کمی بتائی ہے کیونکہ نفاق دل سے تعلق
رکھتا ہے اور قوتِ شعور ہی سے اس کا پتہ لگایا جاتا ہے.اگر منافق ظاہری تو جیہوں کی بجائے
اپنے دلوں کو پڑھنے کی کوشش کریں تو انہیں معلوم ہو جائے کہ ان کے اعمال اصلاح کے
خیال سے نہیں بلکہ بزدلی اور جماعت سے اختلاف رکھنے کے باعث ہیں اور اس طرح ان کو
اپنی بیماری کا علم ہو جائے.مگر وہ اپنے دل کے خیالات کو بھی صحیح طور پر پڑھنے کی کوشش نہیں
کرتے اور اس طرح دوسروں کو دھوکہ دینے کی بجائے اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں.وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ
السُّفَهَاءُ الا إنّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلكِن لَّا يَعْلَمُونَ.سفية کے معنے ہیں (1) خفیف العقل (2) جاہل (3) جس کی رائے میں اضطراب ہو.استقامت نہ ہو (4) ایسا شخص جو دینی و دنیوی عقل عمدہ نہ رکھتا ہو (5) جس کی رائے کی کچھ
قیمت نہ ہو (6) جو شخص اپنی قیمتی اشیاء کو بے سوچے خرچ کردے.لا يَعْلَمُونَ : عَلِمَ سے مضارع منفی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے.اور عَلِمَهُ (يَعْلَمُهُ) کے
معنى تَيَقنَهُ وَعَرَفَةَ کسی چیز کا یقین کر لیا اور اس کو جان لیا.جب سمجھنے کے معنوں میں استعمال ہو
تو اس وقت اس کے دو مفعول آئیں گے اور اگر معرفت کے معنوں میں استعمال ہو تو ایک.علم الآمر کے معنے ہیں اتقنه کسی کام کو مضبوط کیا.عَلِمَ الشَّيْءَ وَ بِالشَّنِي شَعَرَبِهِ
وأحاطه واخرگه کسی چیز کی پوری واقفیت حاصل کر لی.اس کی حقیقت کا احاطہ کر لیا.اس کا
پورا علم حاصل کر لیا.اور الْعِلْمُ کے معنے ہیں ادْرَاكُ الشَّيي يحقیقته کسی چیز کی حقیقت کو
معلوم کر لینا ( اقرب ) پس لا يَعْلَمُونَ کے معنے ہوں گے وہ حقیقت کو نہیں جانتے.آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب مسلمان ان منافقوں سے کہتے ہیں کہ جس طرح
دوسرے شریف آدمی ایمان لائے ہیں اور اپنے عہد کے پکے ہیں تم بھی اسی طرح ایمان لاؤ.264
Page 273
یہ
کیا کہ کبھی ادھر اور کبھی ادھر.دل میں کچھ اور زبان پر کچھ.تو منافق اس کے جواب میں کہتے
ہیں کہ جن لوگوں کی طرح ایمان لانے کا تم ہم کو مشورہ دیتے ہوں وہ تو کم عقل ہیں اور اپنی جانوں
اور مالوں کو بے دریغ لٹا رہے ہیں.کیا تم چاہتے ہو کہ ہم بھی ان کی طرح بے عقل ہو جائیں.ایک مٹھی بھر آدمی ہیں اور ساری دنیا سے مقابلہ شروع کر رکھا ہے.ان کو چاہئے تھا کہ سمجھ سے
کام لیتے اور سب سے تعلقات بنا کر رکھتے جس طرح ہم سب سے تعلق بنا کر رکھتے ہیں.حل لغات میں بتایا جا چکا ہے کہ سفیہ جس کی جمع سُفَهَاءُ ہے سَفَہ سے نکلا ہے اور اس
کے معنے قلت عقل کے بھی ہوتے ہیں.اور بے دریغ اپنے اموال کو لٹانے کے بھی ہوتے
ہیں.قرآن کریم میں بھی یہ محاورہ استعمال ہوا ہے.چنانچہ آتا ہے وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاء
أمْوَالَكُم (نساء (6) اپنے مال ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں نہ دو جوان کو خرچ کرنا نہ جانتے
ہوں اور ان کو ضائع کر دیں.منافقوں کا مسلمانوں کو سُفَهَاء کہنا انہی معنوں میں ہے.ان کا
خیال تھا کہ یہ لوگ نہ اپنی جانوں کی حفاظت کر سکتے ہیں نہ اپنے مالوں کی اور یونہی بے سوچے
سمجھے اپنی جانیں ضائع کر رہے ہیں اور مال لٹا رہے ہیں.لیکن ہم ہوشیار ہیں.ہم مسلمانوں کے
ساتھ بھی بنا کر رکھتے ہیں اور کفار سے بھی.اس طرح ہم دونوں طرف کے خطروں سے محفوظ ہیں.سفية سے مراد منافقوں کی یہ ہے کہ مسلمان اپنی جانوں اور مالوں کو بے سوچے سمجھے برباد
کر رہے ہیں اور ہم اپنی جانوں کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنے مالوں کو بچا رہے ہیں.یہ
اعتراض ہمیشہ بڑھنے والی قوموں پر ہوتا ہے.جب بھی خدا تعالیٰ کسی قوم کو بڑھانا چاہتا ہے
ایسے ہی حالات میں بڑھاتا ہے کہ باوجود اس کے کہ جو قوم کمزور اور بے سامان ہوتی ہے وہ
اسے بے دریغ قربانی کا حکم دیتا ہے جو منافقوں اور دشمنوں کی نظر میں ایک لغو فعل نظر آتا
ہے.کیونکہ وہ قربانی کی قیمت نہیں جانتے.ہاں جب کامیابی حاصل ہو جاتی ہے تو ان کی اولاد
کہتی ہے کہ یہ کامیابی غیر معمولی نہیں اس کا سبب یہ تھا کہ مومن قربانی کرتے تھے اور ان کے
مخالف غافل تھے.گویا پہلے ان کے آباء اور رنگ کا اعتراض کرتے ہیں اور اولاد بالکل الٹ قسم
265
Page 274
کے اعتراض شروع کر دیتی ہے.چنانچہ اسلام کی ابتدا میں تو یہ اعتراض کیا گیا کہ مسلمان تو
بے وقوف ہیں.اپنے مالوں اور اپنی جانوں کو ضائع کر رہے ہیں.اور ایسے طور پر خرچ کر
رہے ہیں کہ نتیجہ کچھ نہ نکلے گا.یونہی اپنے مذہب کے جھوٹے وعدوں کے دھوکے میں آگئے
ہیں.مگر جب اسلام کو غلبہ مل گیا تو اب ان کی اولاد یا اُن کے اظلال یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام کی
ترقی کوئی معجزانہ ترقی نہ تھی.عربوں اور ایرانیوں اور رومیوں کے اخلاق تباہ ہو گئے تھے اور ان
میں قوم کی خاطر قربانی کرنے کا جذبہ نہ رہا تھا اس لئے مسلمان غالب آ گئے.سچ ہے جب
انسان سچائی کو چھوڑتا ہے تو کسی ایک مقام پر کھڑا نہیں ہوسکتا.اسے بار بار اپنی جگہ بدلنی پڑتی
ہے.بھلا کوئی سوچے کہ اگر مسلمانوں کے اندر ایسی ہی کوئی غیر معمولی طاقت موجود تھی اور ان
کے مد مقابل ایسے ہی کمزور تھے تو اندرونی منافق اور بیرونی دشمن ان کی قربانیوں کو اسراف اور
ان کے ارادوں کو جنون کیوں قرار دے رہے تھے.باقی رہا یہ کہ بعض اسباب ان کی تائید میں پیدا ہو گئے تو یہ معجزانہ غلبہ کے خلاف نہیں.اللہ تعالیٰ جب کوئی خبر دیتا ہے تو اس کی تائید میں سامان بھی پیدا کر دیتا ہے.مگر وہ سامان
مومنوں کی کوشش کا نتیجہ نہیں ہوتے.آخر عربوں ، ایرانیوں اور رومیوں کو سچی قربانیوں سے
مسلمانوں نے تو محروم نہ کیا تھا.پھر یہ بھی تو دیکھنا چاہئے کہ دونوں فریق کی طاقت کی باہمی
نسبت کیا تھی.اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عربوں رومیوں اور ایرانیوں سے سچی
قربانی کی روح چھین لی.مگر جس حد تک انہوں نے طاقت خرچ کی مسلمانوں میں تو اس کے
مقابلہ کی بھی ظاہر حالات میں طاقت تھی پھر وہ کیونکر غالب آئے.آخر آیت میں فرمایا کہ اصل میں یہی لوگ اپنے اموال اور جانوں کا نقصان کر رہے ہیں.کیونکہ نہ کفار نے فتح پانی ہے کہ ان کے ساتھ تعلق ان کے لئے مفید ثابت ہو اور نہ مسلمانوں
نے ہارنا ہے کہ ان سے بگاڑا نہیں فائدہ پہنچا سکے لیکن چونکہ یہ آئندہ کی بات ہے.یہ جانتے
نہیں.اور خدا تعالیٰ پر ایمان نہیں کہ اس کی پیشگوئیوں کے ذریعہ سے اس حقیقت کو سمجھ سکیں.266
Page 275
حالانکہ اگر جانتے تو انہیں معلوم ہوتا کہ یہ اس طریق عمل سے اپنے مالوں اور جانوں کو خطرہ میں
ڈال رہے ہیں.وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيْطِينِهِمْ
قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِؤُونَ
ہر شخص جو حق سے دور ہو یا بغض و کینہ سے جل رہا ہو یا سرکش اور باغی ہوشیطان کہلاتا ہے
اس آیت کے مضمون سے ظاہر ہے کہ شیطان کا لفظ قرآن کریم میں یقینی طور پر انسان کے لئے
بھی استعمال ہوا ہے.اس آیت میں شیطاطین سے مراد کفار اور منافقین کے سردار ہیں جو کبر اور نخوت کے
باعث خدا تعالیٰ کے دین سے دور اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہونے سے نفور
رہتے تھے اور دوسرے زیر اثر لوگوں کو بھی صراط مستقیم کی طرف نہیں آنے دیتے تھے.شیطان
سے یہاں ابلیس مراد لینا صحیح نہیں اور نہ اس لفظ کے استعمال سے یہود اور مسیحیوں کے رؤساء کو
گالی دی گئی ہے.کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں
الراكب شَيْطَانٌ وَالرَّاكِبَانِ شَيْطَانَانِ وَالخَلَقَةُ رَكب یعنی سفر کی مصیبتوں کی صورت میں
اکیلا سفر کرنے والا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والا ہے.دوکا بھی یہی حال ہے.تین ہوں
تو مشکلات سے بچ سکتے ہیں.شیطان کے جومعنے میں نے کئے ہیں وہ صحابہ اوراکابر علماء سے بھی ثابت ہیں.اللهُ يَسْتَهْزِى هِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ
اللہ تعالیٰ ان سے استہزاء کرے گا کے یہ معنے نہیں جیسا کہ بعض معترضین قرآن کریم
نے سمجھا ہے کہ نعوذ باللہ مسلمانوں کا خدا استہزاء کرتا ہے.بلکہ اس جگہ جزائے جرم کے لئے
جرم کے الفاظ استعمال کئے گئے ہیں جو عربی زبان کا عام قاعدہ ہے اور قرآن کریم میں مستعمل
267
Page 276
ہے اور مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے استہزاء کی انہیں سزا دے گا.استہزاء جھوٹ کو کہتے ہیں.یعنی کہا کچھ جائے اور اصل میں کچھ اور مراد ہو.اور اس
سے مخاطب کی تذلیل مراد ہو.مگر اللہ تعالیٰ کی نسبت قرآن کریم میں آتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ
اللهِ قِيلًا (نساء 123) یعنی اللہ تعالیٰ سے سچا اور کون ہوسکتا ہے.اسی طرح ہنسی مذاق کرنے
والاشخص لغو گو ہوتا ہے.اور اللہ تعالیٰ کا نام قرآن کریم حکیم رکھتا ہے.یعنی جس کی ہر بات میں
حکمت پوشیدہ ہوتی ہے.پس اللہ تعالیٰ کی نسبت استہزاء کا لفظ محض ان معنوں میں استعمال ہوا
ہے کہ وہ منافقوں کو ان کے استہزاء کی سزا دے گا.حملا ان معنوں کے علاوہ یہ امر بھی یاد رکھنا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کی نسبت جو لفظ استعمال ہو وہ
ان معانی سے جدا ہو جاتا ہے جو بندہ کی نسبت استعمال ہونے کی صورت میں اس میں پائے
جاتے ہیں.اللہ تعالیٰ کی نسبت بولنے کا لفظ بولا جائے تو یہ معنی نہیں کہ اس کی زبان اور ہونٹ
ہیں جن کو اس نے بلایا.بلکہ صرف یہ معنے ہیں کہ بولنے کا جو نتیجہ ہوتا ہے یعنی الفاظ کا پیدا ہونا وہ
اس نے اپنی قدرت سے پیدا کر دیا.اللہ کی نسبت آتا ہے.لَيْسَ كَمِثْلِه شنی (شوری12)
پس اس تاویل کے رُو سے اللہ تعالیٰ کے استہزاء کرنے کے یہ معنے ہوں گے کہ استہزاء کا نتیجہ اس
نے ان کے حق میں پیدا کر دیا.یعنی انہیں ذلیل کر دیا اور لوگوں کی نظروں میں قابل مضحکہ بنادیا.وَيَمدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمُ يمد مد سے نکلا ہے جس کے معنے مہلت دینے کے ہیں.پس اس آیت کے یہ معنے ہوئے کہ باوجود ان کی شرارتوں کے خدا تعالیٰ ان کو مہلت دیتا ہے
کہ وہ سنبھل جائیں مگر وہ طغیان میں بڑھتے جاتے ہیں.یہ معنے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کفار کو طغیان
میں زیادہ کرتا ہے.اس بات کو سورۃ فاطر ر کو ع 4 میں خوب حل کر دیا ہے کہ مہلت گمراہ کرنے
کے لئے نہیں دی جاتی بلکہ اس لئے کہ جو چاہیں اس عرصہ میں تو بہ کرلیں.أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَلَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا
كَانُوا مُهْتَدِينَ
اشْتَرَوُا الضَّللة بالھدی کے ایک معنے تو یہ ہیں کہ ان لوگوں نے ہدایت دے کر گمراہی کو
268
Page 277
خریدلیا ہے.دوسرے معنے یہ ہیں کہ ان لوگوں کے سامنے ہدایت اور ضلالت دونوں پیش کی گئی
تھیں.انہوں نے ضلالت اختیار کر لی اور ہدایت ترک کر دی.پہلے معنوں کی بنیاد اس بات پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک انسان کو فطرت صحیحہ عطا کی
ہے.اور اسے بہترین قومی دتے ہیں.جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :.فِطْرَتَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ
النَّاسَ عَلَيْهَا (روم (31) اللہ تعالیٰ کی وہ فطرت جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے.اور
دوسری جگہ فرماتا ہے.لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (تین5) کہ ہم نے انسان
کو بہترین طاقتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے اور اسے اعلیٰ قومی دتے ہیں.پھر اس کے بعد وہ اپنی
یا اپنے والدین کی خرابیوں اور بداعمالیوں کی وجہ سے فطرت صحیحہ اور پاک قویٰ سے محروم ہو جاتا
ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا.مَا مِن مَوْلُودٍ إِلَّا يُوَلِّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوهُ
يُهَوْدَانِهِ أَوْ يُجْسَانِهِ أَوْ يُنيَّرَانِهِ مسلم) جلد 4 کتاب القدر) کہ بچہ تو فطرۃ صحیحہ پر پیدا
ہوتا ہے مگر اس کے والدین اس کے بچپن سے فائدہ اٹھا کر اسے اپنے دین پر کر لیتے ہیں اور
اسے یہودی یا مجوسی یا عیسائی بنا لیتے ہیں گویا وہ ان کی فطرتی ہدایت کو قربان کر دیتے ہیں اور
اس کے بدلہ میں اسے گمراہی خرید دیتے ہیں.یا پھر وہ بڑا ہو کر خود اپنی اچھی طاقتوں کو بُرے
طریق پر استعمال کر کے خراب کر لیتا ہے.پس اس جگہ ہدایت سے وہ فطرتی نیک طاقتیں مراد
ہیں جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہیں.اور اشتری کا مطلب یہ ہے کہ شریر لوگ ان
پاک ٹوٹی کو جو اُن کی ترقی کے لئے ان کو دیئے گئے تھے بُرے مواقع پر استعمال کر کے ان سے
گمراہی اور ضلالت خرید لیتے ہیں اور دینی اور دنیوی دونوں فائدوں سے محروم ہو جاتے ہیں.دوسرے معنوں کی بنیاد اس بات پر ہے کہ ایک طرف تو خدا تعالیٰ نے انسان کو نیکی اور
بدی کے امتیاز کی مقدرت اور اختیار دیا ہے.دوسری طرف نبیوں کے ذریعہ اس کے پاس نیکی
کی تعلیم اور ہدایت بھیج دیتا ہے مگر ساتھ ہی شیطان اپنی بُری تعلیم اس کے سامنے پیش کرتے
ہیں.جولوگ خدا تعالیٰ کی دی ہوئی عقل سے کام نہیں لیتے وہ خدا تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ہدایت کو
269
Page 278
چھوڑ دیتے ہیں اور شیطان یا اس کے چیلوں کی پیش کی ہوئی گمراہی کی باتوں کو قبول کر لیتے ہیں
اور اس طرح ہدایت کورڈ کر کے ضلالت کو اختیار کرنے والے ہو جاتے ہیں.فَمَارَ بِحَت تجارتهم - چونکہ کفار نے ایک چیز چھوڑ دی اور دوسری اس کے بدلہ میں
لے لی اس لئے اس کا نام تجارت رکھا گیا ہے.فرماتا ہے کہ انہوں نے اپنے خیال میں ایک
مفید تجارت کی ہے کہ خدا تعالیٰ کی دی ہوئی نیک فطرت کو ترک کر کے بُری باتوں کو اختیار کر
لیا ہے.یا خدا تعالیٰ کی بھیجی ہوئی تعلیم کو چھوڑ کر شیطانی باتوں کو اختیار کر لیا ہے اور وہ سمجھتے ہیں
کہ اس طرح وہ بہت فائدہ اٹھائیں گے.لیکن انہیں کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا بلکہ وہ نقصان
اٹھائیں گے اور یہ سودا انہیں بہت مہنگا پڑے گا.وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ یہ نتیجہ پہلے نتیجہ کے علاوہ ہے.اس میں بتایا ہے کہ ان کو صرف
یہی نقصان نہیں ہوگا کہ وہ دنیا میں ذلیل ہوں گے اور نقصان اٹھائیں گے.بلکہ اس کا نتیجہ یہ
بھی نکلے گا کہ وہ ہدایت سے محروم رہیں گے اور ان کی عاقبت بھی خراب ہوگی.اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر فعل کے دو نتیجے نکلتے ہیں.ایک نتیجہ تو اس فعل کے ساتھ
ہی نکلتا ہے اور دوسرا اس کے بعد پیدا ہوتا ہے.مثلاً ایک انسان چوری کرتا ہے تو اس کا ایک
نتیجہ تو یہ نکلتا ہے کہ وہ ذلیل ہو جاتا ہے اور پکڑا جاتا ہے اور قید ہوتا ہے یا اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے
یا اور کوئی سزا پاتا ہے.دوسرا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہدایت کے قبول کرنے کی قابلیت اس میں
سے جاتی رہتی ہے اور وہ ہدایت سے دُور ہو جاتا ہے.اسی طرح ہر نیکی کا نتیجہ اس کے ساتھ ہی
نکلنا شروع ہو جاتا ہے.مثلاً اس نیکی کی وجہ سے اس کے اپنے دل میں خوشی پیدا ہوتی ہے اور
لوگوں میں اس کی عزت قائم ہو جاتی ہے اور وہ اسے اچھا خیال کرنے لگ جاتے ہیں.دوسرا
نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر ہدایت قبول کرنے کی قابلیت بڑھتی جاتی ہے اور وہ ہدایت میں
ترقی کرتا جاتا ہے.وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ میں اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ دوسرا نقصان
انہیں یہ پہنچا کہ وہ ہدایت سے دور ہی دور ہوتے چلے گئے ہیں.ماخوذ از تفسیر کبیر از حضرت خلیفة المسیح الثانی)
270
Page 279
حضرت خلیفہ المسیح الثانی نے خطبہ جمعہ فرمودہ 16 جنوری 1914 میں سورہ بقرہ کی آیات
2 تا 6 کی تلاوت کی اور فرمایا :
یہ کتاب هُدًى لِلْمُتَّقِينَ ہے.یہ کتاب متقیوں کو ہدایت دیتی ہے.متقی کون لوگ
ہیں؟ متقی وہ لوگ ہوتے ہیں جو لوگ ایمان بالغیب رکھتے ہیں اور نمازوں کو قائم کرتے ہیں
اور خدا کی دی ہوئی نعمتوں کو اس کے رستے میں خرچ کرتے ہیں اور قرآن کریم پر ایمان رکھتے
ہیں اور جو کتابیں قرآن کریم سے پہلے اتریں اور جو اس کے بعد الہام ہوں گے ان پر اور قیامت
پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں.متقیوں کو یہ کتاب راستہ دکھلاتی ہے.اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ یہ کتاب جو پہلے ہی سے متقی ہے اس کو تو راستہ دکھلاتی ہے لیکن
دیگر عوام الناس کے لئے پھر کون سی تعلیم ہے جو ان کی رہنمائی کرے، کتاب تو وہ چاہئے جو
سب کی یکساں راہ نمائی کرے.اس قسم کے اعتراض کرنے والوں نے تدبر سے کام نہیں لیا.اگر وہ سوچتے تو ان کو معلوم
ہو جا تا کہ ہر ایک انسان جب اس سے پوچھا جائے کہ آپ کیا ہیں تو وہ اپنا اعلیٰ سے اعلیٰ دعویٰ
ہی پیش کرے گا نہ کہ پہلے ادنی درجوں کو گننے بیٹھ جائے اور بعد میں بتلائے کہ میں یہ ہوں.مثلاً
اگر کوئی کسی تحصیلدار سے سوال کرے کہ آپ کون ہیں؟ تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں پہلے پٹواری
یا گرد اور تھا.پھر نائب تحصیلدار پھر اب تحصیلدار ہوں بلکہ وہ یہی کہے گا کہ میں تحصیلدار ہوں.اسی طرح جب کوئی کسی ڈاکٹر سے سوال کرے کہ آپ کون ہیں تو کیا وہ پہلے یہ کہے گا کہ میں
نے پہلے پرائمری پھر مڈل پھر انٹرنس پاس کر کے پھر میں نے ڈاکٹری کی جماعت پڑھی
اور اب میں ڈاکٹر ہوں.اسی طرح اگر کوئی ایم.اے سے پوچھے تو وہ پہلے ہی آپ کو ایم.اے
بتلائے گا نہ کہ جماعتیں گنے بیٹھے گا.اسی طرح قرآن کریم کی تعلیم ہے.یہ ہر ایک کو ہدایت
دے سکتی ہے خواہ کوئی چھوٹا ہو یا بڑا یا کسی طرح کا ہو.میدان مذاہب میں اسلام نے بھی اپنے آپ کو پیش کیا ہے.اس پر یہ سوال ہو سکتا تھا کہ
271
Page 280
تمہاری کیا خصوصیت ہے جو ہم تمہیں اختیار کریں.دکانوں والے اپنی دکانوں کے سامنے
سائن بورڈ لگادیا کرتے ہیں اور وہ اس پر اپنی اپنی خصوصیات لکھ دیتے ہیں ، کوئی لکھتا ہے کہ
یہاں سے مال عمدہ اور ارزاں ملے گا.کوئی لکھتا ہے یہاں سے دیسی مال مل سکتا ہے.کوئی
لکھتا ہے کہ یہاں سے اعلیٰ درجہ کا اور دیر پاولایتی مال ملے گا.غرض اسی طرح ہر ایک کوئی نہ
کوئی اپنی خصوصیت لکھ دے گا.گاہک بھی کسی خصوصیت کی وجہ سے ہی وہاں آئے گا.اسی
طرح مذاہب میں جھگڑا ہے.ہر ایک اپنے آپ کو سچا کہتا ہے.اسلام میں کون سی خوبی ہے
کہ جو یہ ایک نیا مذہب پیش کیا جاتا ہے.کوئی ایسی خوبی ہونی ضروری ہے جو پہلے مذاہب
میں سے کسی ایک میں بھی نہ ہو.اگر پہلے میں کوئی فرق نہ ہو تو کسی کو کیا ضرورت ہے کہ وہ اپنا
مذہب ترک کر کے اسلام میں داخل ہو.قرآن کریم کے شروع میں ہی اس سوال کو حل کر دیا ہے.هُدًى لِلْمُتَّقِينَ.تمام مذاہب
کی آخری بات اور آخری معیار یہ ہے کہ وہ انسان کو متقی بنا دیتے ہیں.ہندو ہو یا عیسائی،
یہودی ہو یا کوئی اور، یہ سب یہی کہتے ہیں کہ ہمیں مان لو تو پاک ہو جاؤ گے.مگر ہم کہتے ہیں کہ
اس کا ثبوت کیا ہے.سب مذاہب والے یہی کہتے ہیں کہ اس کا نتیجہ تمہیں آخرت کو چل کر
معلوم ہو جائے گا، فی الحال تمہارے لئے مان لینا ہی کافی ہے.قبول کر لینے کی غرض تو یہ ہے
که مولی راضی ہو جاوے.آخرت میں جا کر اگر معلوم ہوا کہ یہ راہ جس پر ہم چلتے تھے وہ غلط تھی تو
اس وقت پھر کیا فائدہ ہوگا.وہاں سے تو انسان واپس نہیں آسکتا کہ واپس آکر دوسرا صحیح طریق
اختیار کر لیوے.قرآن کریم کا دعوی ہے کہ میں صرف متقی ہی نہیں بنا دیتا بلکہ میں ہدایت
دیتا ہوں اور ایک دروازہ کھول دیتا ہوں جس سے متقی بننے کے ثمرات سے اسی دنیا میں متمتع ہو
سکتے ہیں اور پھر متقی سے آگے جو بلند درجات ہیں وہ حاصل ہوتے ہیں.اس کی مثال ایسی ہے کہ مثلاً کوئی اعلیٰ افسر ہو اور ایک آدمی اس کو ملنا چاہتا ہو تو اس آدمی کو
ایک آدمی تو کہتا ہے اس کے دروازے تک میں پہنچا سکتا ہوں اور دوسرا ایک آدمی ہے جو
272
Page 281
اسے کہے کہ میں آپ کو اندر اس کے پاس پہنچا سکتا ہوں اور اس سے ملاقات کروا سکتا ہوں.تو
وہ دونوں میں سے کس کی بات مانے گاوہ اس کی بات مانے گا اور اسی کے ساتھ ہولے گا جو
اسے اس کے ساتھ ملا دینے کا وعدہ کرتا ہے اور اندر لے جائے گا.تمام مذاہب کا دعوی یہی
ہے کہ ہم دروازے تک پہنچا دیں گے مگر اسلام صرف یہی دعوی نہیں کرتا کہ میں دروازے
تک پہنچادوں گا بلکہ وہ اندر لے جانے کا دعویٰ کرتا ہے اور خدا سے ملا دینے کا وعدہ کرتا ہے.اسلام پر چلنے سے تمہیں اسی دنیا میں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تم پر راضی ہے.منتقی جو اپنی طرف سے تمام نیک اعمال میں کوشش کرتا ہے اور تمام کاموں میں اللہ کی
خشیت مدنظر رکھتا ہے ، اپنی کوشش ختم ہونے کے بعد پھر یہی باقی رہ جاتا ہے کہ دوسری
طرف سے کوشش شروع ہو جاتی ہے.پس اپنی طرف سے انتہائی کوشش کر کے جو اسلام
کے دروازے تک پہنچ جاتے ہیں یہ کتاب انہیں محبوب سے ملا دیتی ہے.ہر زمانے میں اسلام
میں مجد داور امام آتے رہے ہیں اور تمام مذاہب میں سے کسی ایک میں ایسا نہیں پایا جا تا.کوئی
آدمی کسی کی دکان میں جائے تو اگر وہ اپنی مطلوبہ چیز اس دکان میں نہ پائے تو وہ وہاں داخل نہیں
ہوتا جس دکان میں اس کی مطلوبہ چیز پائی جائے گی وہ اسی دکان میں داخل ہوگا.تمام مذاہب
نے خدا کے حضور پہنچادینے سے انکار کیا ہے.صرف اسلام کا ہی یہ دعویٰ ہے کہ وہ خدا کے
حضور پہنچا دیتا ہے اس کی تصدیق ہم دیکھتے ہیں ہر زمانے میں ہورہی ہے اور ہرزمانہ میں
خدا کی طرف سے مخلوق کی ہدایت کے لئے اس کے بندے آتے رہتے ہیں.کوئی آدمی اگر
ایسا ہے کہ وہ بی.اے کو پڑھا سکے تو وہ الف با بھی پڑھا سکتا ہے.ای طرح هدی للمتقین سے مراد یہ ہے کہ یہ اعلی درجہ تک پہنچا سکتا ہے تو کیا ادنی درجہ کے لوگوں کو
ادنی باتیں یہ نہیں سمجھا سکتا اور ان کو ہدایت نہیں دے سکتا.اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جو دعوئی میں بھی
بڑھ گیا اور یہی لوگوں کی غرض کو پورا کرنے والا ہے اسی وجہ سے تمام مذاہب پر فائق ہے.( خطبات محمود سال 1914 صفحہ 22 تا25)
حضرت خلیفہ المسح الثانی نے خطبہ جمعہ فرمودہ 23 جنوری 1914 میں سورہ بقرہ کے
273
Page 282
پہلے رکوع کی تلاوت کی اور فرمایا:
یہ سب سے پہلا رکوع ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے نزول اور
رسول الله علی ایم کی بعثت کی غرض بیان کی ہے اور وہ یہ ہے کہ کتاب انسان کو متقی بنا کر اعلیٰ
سے اعلی درجہ تک پہنچاتی ہے اور ان دینی و دنیوی ترقیات کی راہ دکھاتی ہے جن پر ایک انسان
پہنچ سکتا ہے.چونکہ ہر قوم کے نقطہ خیال سے متقی کی جدا تعریف ہے، ہندؤں کے نزدیک
متقی اور ہے یہود کے نزدیک اور عیسائیوں کے نزدیک اور.اس لئے اب بتانا ہے کہ
ہمارے نزدیک متقی کون ہے.دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں.ایک وہ جن کا ظاہر و باطن یکساں
ہے جو خیالات ان کے جی میں ہیں اس کے مطابق ان کا عمل ہے.دوسرے وہ جن کا اندر کچھ
ہے اور باہر کچھ، ظاہر کچھ باطن کچھ.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ متقی وہ ہے کہ ہم خواہ کتنے ہی غیب میں ہوں ہم پر اس کا ایمان کامل
رہتا ہے اور پھر اور جو چیزیں غیب میں ہیں ، ان پر ایمان لاتا ہے.اس کے دل میں کھوٹ
نہیں ہوتا.پھر وہ نمازوں کو قائم کرتا ہے.یہ تو اپنے خالق سے تعلقات کی نسبت فرمایا.دوسرا
تعلق مخلوق سے ہے.سو اس کے لئے ارشاد ہوتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے اس کو دیا ہے وہ اس
میں سے خرچ کرتا رہتا ہے.جس شخص کے مخلوق سے تعلقات عمدہ نہیں اس کے تعلقات اپنے
خالق سے بھی اچھے نہیں رہ سکتے ، اس لئے قرآن مجید نے دونوں طرفوں کو لیا ہے.جو بڑی لمبی
لمبی نمازیں پڑھتا ہے اور خدا کی مخلوق سے بد معاملگی کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے
کوئی شخص اپنے حاکم کے سامنے نہایت مؤ ڈب کھڑا ہو مگر جب وہ اپنے حاکم کے سامنے سے
ہے تو اپنے ماتحتوں پر ظلم کرنا شروع کر دے.یہ شرفاء کا کام نہیں.خدا نے اپنی مخلوق پر شفقت
کرنے کو بھی عبادت فرمایا ہے.چنانچہ لکھا ہے کہ قیامت کے دن خدا تعالیٰ فرمائے گا کہ
میں ننگا تھا تم نے مجھے کپڑا نہ پہنایا، بھوکا تھا مجھے کھانا نہ کھلایا، پیاسا تھا مجھے پانی نہیں پلایا، بیمار
تھا میری بیمار پرسی نہیں کی.وہ بندے عرض کریں گے کہ یہ آپ کی شان کہاں ہے.اللہ تعالیٰ
274
Page 283
فرمائے گا میری مخلوق میں سے چھوٹے سے چھوٹے سے بیمار یا بھوکے پیاسے کے ساتھ
ہمدردی کرنا گویا میرے ساتھ ہمدردی کرنا ہے.خدا نے اپنی بخشی ہوئی نعمتوں کی کوئی حد بندی نہیں کی جو کچھ بھی کسی کو خدا نے دیا ہے
چاہئے کہ اس میں سے کچھ اس دینے والے کے نام پر خرچ کرے.اگر علم دیا ہے تو علم میں
سے.مال دیا ہے تو مال میں سے.اس صفت سے متصف انسان دوسروں کے حقوق تلف
نہیں کرتا کیونکہ جو اپنے پاس سے بھی کچھ دینے کی عادت رکھتا ہو وہ کبھی ایسا نہیں ہوسکتا کہ کسی
کے مال پر بیجا تصرف کرے.غرض منتقی کے خالق اور مخلوق دونوں سے تعلقات نہایت عمدہ
ہوتے ہیں وہ اپنے اندر فرمانبرداری کی روح رکھتا ہے.نہ صرف قرآن مجید پر ہی ایمان
رکھتا ہے بلکہ اس سے پہلے جو کتابیں آئیں ان پر بھی ایمان لاتا ہے اور قرآن مجید کے بعد جو
وحی نازل ہو اس پر بھی ایمان لانے کو تیار ہے.اس کا اپنا کوئی نفس باقی نہیں رہتا ، وہ
ہر حالت میں خدا کی رضا جوئی کا آرزو مند رہتا ہے.ایسے لوگوں کی نسبت فرماتا ہے کہ یہ اپنے
رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور جو ہدایت پر چلیں گے وہی کامیاب اور منصور ہوں
گے.بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف ہاتھ میں ہاتھ دینے سے نجات ہو جاتی ہے مگر ایسا ہر گز نہیں.عمل کی ضرورت ہے جو خدا کے فضلوں کا جاذب ہے.اللہ کا یہ احسان کیا کم ہے کہ اس نے
ہماری ہدایت کے لئے ایسی روشن کتاب عطا فرمائی.اس احسان کے شکریہ میں تو اور بھی اس
کافرمانبردار بننا چاہیئے، نہ یہ کہ الٹا خدایا اس کے فرستادہ پر احسان رکھیں کہ ہم ایمان
لائے.اگر کوئی شخص رستہ سے بھٹک گیا ہو اور دوسرا اسے سیدھے راستہ پر چلا دے تو اب یہ
اور
اس راستہ پر چل کر راہنما پر احسان نہیں جتا سکتا کہ دیکھ میں تیرے بتائے ہوئے رستہ پر چل
رہا ہوں بلکہ اسے ممنون ہونا چاہئے کہ مجھ بھولے ہوئے کو رستہ دکھایا.خطبات محمود سال 1914 صفحہ 26 تا 28)
حضرت خلیفہ المسح الثانی نے خطبہ جمعہ فرمودہ 6 فروری 1914ء میں سورہ بقرہ کے پہلے
رکوع کی آخری دو آیات إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرُهُمْ
275
Page 284
لا يُؤْمِنُونَ خَتَمَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ
عظیم - کی تلاوت کی اور فرمایا:
دنیا میں دو ہی قسم کے آدمی ہوتے ہیں.ایک تو وہ لوگ ہیں کہ وہ کسی چیز کا انکار کریں
تو اپنی کم علمی کی وجہ سے کرتے ہیں اور جب ان کو کوئی خوبی ، کوئی نیکی اچھی طرح سے سمجھادی
جاوے تو وہ مان لیتے ہیں.دوسرا گروہ وہ لوگ ہیں جو کہ کسی بات کا انکارا اپنی کم علمی کے سبب
سے نہیں کرتے بلکہ وہ ایک بغض اور ضد، تعصب اور ہٹ دھرمی کے سبب سے انکار کرتے
ہیں.جولوگ کہ کم علمی کی وجہ سے انکار کرتے ہیں ان کو سمجھانا بالکل آسان ہوتا ہے اور وہ ہدایت
کے بالکل قریب ہوتے ہیں.اور دوسرا فریق جو تعصب اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے انکار
کرتے ہیں ان کے لئے سمجھانا کبھی بابرکت نہیں ہو سکتا اور وہ ہدایت نہیں پاسکتے.ہر ایک نبی
کے وقت میں ایسے گروہ پیدا ہوتے رہے ہیں.ایسے لوگ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسرں
کے لئے بھی گمراہی کا موجب بنتے ہیں....اللہ تعالیٰ نے فرمایا دو گروہوں میں سے جولوگ کہ کسی بے علمی کی وجہ سے انکار کرتے ہیں
اور جب علم ہو گیا تو مان لیتے ہیں ایسے لوگ کامیاب ہوں گے.اور جولوگ کہ ضد اور تعصب
اور ہٹ دھرمی کو کام میں لاتے ہیں ایسے لوگوں کو تیرا ڈ رانا یا نہ ڈرانا برا بر ہے، ایسے لوگ
ہدایت نہیں پاسکتے.خدا تعالیٰ بڑا غیور ہے.بہت سے انسان باغیرت ہوتے ہیں.انسان کی
فطرت میں غیرت کے سمجھانے کے لئے یہ رکھا ہے کہ انسان جب کسی کے ساتھ کوئی احسان
کرے یا کسی پر خوش ہو کر اس کو انعام دے اور آگے اس کی بے قدری ہو تو اس سے انعام لے
لیتا ہے اور پھر اس کو انعام نہیں دیتا.اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَئِن شَكَرْتُمْ
لأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ.(ابراهیم : 8) تم اگر میری نعمتوں کی قدر
کرو گے تو میں تم پر انعام زیادہ کروں گا.یہاں تاکید فرمائی ہے کہ میں ضرور تمہاری نعمتوں کو
زیادہ کروں گا.یہ فطرت انسانیہ سمجھاتی ہے.ہر ایک انسان اپنے نفس میں سمجھ سکتا ہے کہ اگر وہ
کسی پر انعام کرے اور وہ آگے سے انعام کی بے قدری کرے تو پھر انسان اس پر کبھی انعام نہ
276
Page 285
کرے گا اور اسے کچھ نہ دے گا.اگر انسان کسی کو کپڑا دے اور وہ وہیں اس کے سامنے چیر
پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دے یا کھانے کی چیز دے اور وہ کتے کے آگے پھینک دے.یا دودھ
دیا اور اس نے پھینک دیا اور انعام کی بے قدری کی تو پھر اسے انعام دینے کو جی نہیں
چاہتا اور انسان پھر دوبارہ اس پر انعام نہیں کرے گا.انسان تو اگر انعام کی بے قدری ہوتے
دیکھے تو جس پر انعام کرے اس سے سب انعام چھین لیتا ہے اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کے انعاموں
کی بے قدری کرے تو اللہ تعالیٰ چونکہ رب العالمین ہے ( ہمارے تو حوصلے پست ہوتے ہیں
اس لئے سب انعام اس سے چھین لیتے ہیں ) اللہ تعالیٰ جس نعمت کی ناقدری دیکھے وہی اس
سے چھینتا ہے اور صرف اس کی سزا دیتا ہے جس کا خلاف ہو.انعامات دو قسم کے ہوتے ہیں جسمانی اور روحانی.جسمانی انعامات میں سے آنکھ کو لے
لو.جو شخص کہ آنکھ سے کام نہ لے اور اسے استعمال میں نہ لائے تو آنکھ نا کارہ ہو جاتی ہے اور تباہ
ہو جاتی ہے پھر وہ کبھی کام نہیں دے سکتی..بعض ہندولوگ ہاتھوں کو سکھا دیتے ان سے کام
نہیں لیتے اور ان کو یو نہی کھڑا رکھتے ہیں تو وہ ہاتھ سوکھ کر نکھے ہو جاتے ہیں.غرض انسان جس
عضو سے کام لیوے وہ ترقی کرتا ہے اور جسے بیکار چھوڑ دے وہ نکما ہو جاتا ہے.جس طرح انسان
کے اعضاء کے ساتھ معاملہ ہے ایسے ہی روحانی اعضاء کا معاملہ ہے.ہر ایک عضو کے دوکام
ہوتے ہیں روحانی اور جسمانی.اگر کوئی آدمی عقل سے کام نہ لے تو اس کی عقل ماری جاتی ہے
اور جو حافظہ سے کام نہ لے اس کا حافظہ نکما ہو جاتا ہے.ایسے ہی جو شخص دانائی سے کام نہ لے تو
اس کا بھی یہی حال ہو گا.اسی طرح اگر کوئی شخص قرآن کریم کو نہ پڑھے اور اگر وہ قرآن کریم کی
ایک آیت کو بھی غور سے نہ دیکھے اور اسے سمجھنے کی کوشش نہ کرے تو وہ روحانی معاملات کے
سمجھنے سے قاصر رہتا ہے.ایسے لوگ جو قرآن کریم کے سمجھنے میں اپنے افکار سے کام نہ لیں
اور اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں تو ایسے لوگوں کے دلوں پر مہر ہو جاتی ہے اور وہ کچھ سمجھ نہیں
سکتے.اور جس طرح ظاہری اعضاء کو کام میں نہ لایا جائے تو وہ بے کار ہو جاتے ہیں ایسے ہی ان
کی دل کی آنکھوں پر پردے پڑ جاتے ہیں اور ان کے دل کی بینائی ماری جاتی ہے اور بالکل
277
Page 286
ضائع ہو جاتی ہے.اور ان کے کانوں میں بوجھ پڑ جاتے ہیں وہ کچھ نہیں سن سکتے اور ان کو
سزادی جاتی ہے اور انہیں سخت عذاب ہوگا.اور جو ایمان لے آتا ہے اور ماننے اور ہدایت کو
قبول کرنے کے لئے تیار رہتا ہے اسے تو اور زیادہ انعام ملتے ہیں اور وہ کامیاب و مظفر ومنصور
ہوتا ہے.اور جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے اور وہ کفر کرتا ہے تو اس سے وہ نعمتیں
چھین لی جاتی ہیں اور اسے عذاب ملتا ہے.( خطبات محمود سال 1914ء صفحہ 29 تا32)
وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمُ
مُؤْمِنِينَ
حضرت خلیفہ المسیح الثانی نے خطبہ جمعہ فرمودہ 13 فروری 1914ء میں سورہ بقرہ کے
رکوع دوم کا ایک حصہ پڑھ کر فرمایا:
اللہ تعالیٰ نے دو گروہوں کا ذکر پہلے رکوع میں بیان فرمایا ہے جو قرآن کریم کے نزول
کے وقت ہوئے تھے.ایک وہ گروہ جوایمان لے آئے اور دوسرا گروہ جنہوں نے نہ
مانا.پھر ان کا نتیجہ بیان فرمایا اور بتلایا کہ ان کو کیا اجر ملے گا.فرمایا کہ جنہوں نے مان لیا وہ تو
کامیاب اورمظفر اور منصور ہو گئے اور جنہوں نے نہ مانا ، ان کو عذاب عظیم ہوگا اور وہ تباہ
ہو جائیں گے.اب فرمایا کہ ایک گروہ اور بھی ہے جو ان دونوں گروہوں میں سے اپنے آپ کو الگ
بتاتا ہے.مگر قرآن کریم نے ان کو دوسرے گروہ میں شامل کیا ہے.وہ اپنے مونہوں سے کہتے
ہیں کہ ہم ایمان لائے ، ہم نے اللہ کو مان لیا اور یوم آخرت کو بھی مانتے ہیں لیکن درحقیقت وہ
مومن نہیں.ان
کا اندرون و بیرونہ ایک نہیں ہے.وہ منہ سے کچھ کہتے ہیں اور ان کے دلوں میں
گند بھرا ہوا ہے.ایسے لوگوں کا منہ سے اور اقرار کرنا نفع رساں نہیں ہے.اور یہ مومن نہیں
ہیں بلکہ یہ بھی منکرین میں سے ہیں اور انہی میں شامل ہیں.ایسوں کی اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں
ہے.تو یہ ایک تیسرا گروہ پیدا ہو گیا.وہ اپنے منہ سے ایمان کا اقرار کرتے ہیں اگر ان کے
278
Page 287
دلوں میں بھی وہی ہو جو وہ منہ سے کہتے ہیں ، تب تو ٹھیک ہے مگر وہ ایسے نہیں اس لئے مومنین
کے ساتھ شامل نہیں ہو سکتے.انہوں نے اللہ کو چھوڑ دیا اور مومنین کو چھوڑ دیا...اور اب
سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم ان کو بلاک کردیں گے.یہ ایسا ہر گز نہیں کر سکتے.بلکہ انہوں نے اپنی ہی
جانوں کو ہلاکت میں ڈال دیا.لیکن یہ مجھ نہیں سکتے اور ان کو معلوم نہیں ہوتا.ہر زمانہ میں ایسے
لوگ پیدا ہوتے رہتے ہیں.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسوں سے تمہارا کوئی تعلق نہیں.وہ خدا کو بھی اور مومنوں کو بھی
چھوڑتے ہیں.ان کے دلوں میں ایمان نہیں اور نہ ہی ان کو حقیقی طور پر خدا کا ڈر ہے.جس
شخص کے دل میں حقیقی طور پر اللہ تعالیٰ کا ڈر اوراس کی عظمت ہوتو وہ آوروں سے نہیں
ڈرتا.ان منافق لوگوں کے دل میں لوگوں کا ڈر ہے.یہ سمجھتے ہیں کہ اگر فریقین سے ہم تعلق
نہیں رکھیں گے تو ہم دکھوں سے محفوظ نہیں رہ سکتے.حالانکہ انسان کو ہمیشہ اس بات کا خیال
رہتا ہے کہ کسی ایسے سے اس کی عداوت یا لڑائی نہ ہو جو اس کے آقا کا دوست ہو یا آقا اس کی
عداوت کی وجہ سے ناراض ہو.بلکہ ایسے موقعہ سے حتی الوسع انسان بچتا ہے اور اس شخص سے
دوستی رکھتا ہے جو اس کے آقا کا دوست ہو اور آقا کے دشمن سے یہ دشمنی رکھتا ہے.انسان تو
انسان کتے بھی ایسا ہی کرتے ہیں.جن لوگوں کو یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ ہمارے مالک کے پاس
آتے ہیں اور اس کے دوست ہیں، ان کو تو کچھ نہیں کہتے اور جس کو یہ دیکھیں کہ یہ کبھی ہمارے
مالک کے پاس نہیں آیا تو وہ اگر آوے تو اسے بھونکتے ہیں اور اسے کاٹنا چاہتے ہیں.جب کتے
کا یہ حال ہے کہ جب اس کے مالک سے کسی کا تعلق ہو تو وہ اسے نہیں کاٹتا تو جب انسان
اللہ تعالیٰ سے جو خالق و مالک اور احکم الحاکمین رب العالمین ہے اپنا تعلق پیدا کر لے گا تو
ضرور وہ ہر بلا سے محفوظ رہے گا اور اسے کوئی تکلیف نہ ہوگی اور اسے کسی موذی چیز سے ایذاء نہ
پہنچے گی.حضرت مسیح موعود کو الہام ہوا کہ آگ ہماری غلام بلکہ غلاموں کی غلام ہے“
جب طاعون پڑی تو اس وقت سے پہلے یہ الہام آپ کو ہوا تھا.پہلے آپ کو دکھلایا گیا تھا
279
Page 288
کہ طاعون اس طرح تباہ کرے گی اور اس طرح نافرمانوں کو ہلاک و بر باد کرے گی.اس سے
انسان کو ڈرہوسکتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمیں بھی اس سے گزند پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ آگ
ہماری غلام بلکہ غلاموں کی غلام ہے.یعنی ہم تمہیں طاعون سے بچاویں گے بلکہ تمہارے
غلاموں اور ان کے غلاموں کی بھی حفاظت کریں گے تو جب حاکم راضی ہو تو ما تحت خود بخود
راضی ہو جاتا ہے.اس پر غور کرنے سے کھلتا ہے کہ کیونکر انسان تمام قسم کے خوفوں سے محفوظ رہ
سکتا ہے.جو ایسا نہیں کرتے ان کو خدا تعالیٰ پر پورا ایمان نہیں ہے.نبی کریم عالم نے
جب اپنا دعویٰ کیا تو سب سے زیادہ خطر ناک بات جس کی لوگوں نے سخت مخالفت کی وہ لا الہ
الا اللہ کا پیش کرنا تھا.وہ لوگ محمد رسول اللہ کو ماننے کو تیار تھے مگر لا إله إلا اللہ کو وہ نہیں مانتے تھے.چنانچہ وہ
لوگ آپ کے پاس آئے اور آ کر عرض کیا کہ اگر آپ کو حکومت کا شوق ہے تو ہم آپ کو اپنا
بادشاہ بنانے کو تیار ہیں اور ا گر آپ کو مال کی خواہش ہے تو ہم اتنا مال جمع کر سکتے ہیں جتنا تم
چاہو اور اگر شادی کرنا چاہو تو ہم تم کو خوبصورت سے خوبصورت بیوی لا دیتے ہیں اور اگر تم بیمار ہو تو
آپ کا علاج کروانے کو تیار ہیں.تو نبی کریم عالم نے فرمایا کہ سورج اور چاند اگر میرے
دائیں بائیں لا کر رکھ دیئے جاویں تو بھی میں لا الہ الا
اللہ کی تعلیم سے نہیں رک سکتا.ان لوگوں
کی مخالفت صرف لا اله الا اللہ کے سبب سے تھی.وہ بتوں کے پجاری تھے اور بت بنا بنا کر
بیچا کرتے تھے اور وہ ان کے رزق کا ایک ذریعہ بنے ہوئے تھے.وہ اس لا اله الا اللہ کی تعلیم
سے بڑھ کر کوئی اور خطرناک بات نہیں سمجھتے تھے.وہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے اس تعلیم کومان
لیا تو ہمارا ستیا ناس ہو جائے گا تو جس شخص کا یہ حال ہے وہ کیوں مخالفت نہ کرے گا.تو ایسی
حالت میں جبکہ نبی کریم ملایم ایم اکیلے تھے اور باوجود اس کے کہ تمام عرب مخالف تھا، آپ اس
کہنے سے نہیں رکے اور آخر کار کامیاب و مظفر و منصور ہو گئے.پس جو شخص پھر ایسا ہو جاوے
لوگ اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے.280
Page 289
اور جو شخص ایسا نہیں ہے اور وہ جماعت میں داخل نہیں ہوتا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں
ہوتا جب تک کہ وہ بیعت کر کے جماعت میں داخل نہ ہو جاوے.اس قطع تعلق کا نقصان ان کی
اپنی جانوں پر ہے اور کسی کو اس کا نقصان نہ ہوگا.ظاہری دشمن کا مقابلہ آسان ہوتا ہے کھیچی
ہوئی تلوار کا مقابلہ انسان آسانی سے کر سکتا ہے مگر زہر کی پڑیا کا مقابلہ نہیں کرسکتا.تلوار سے تو
بھاگ سکتا ہے اس کا مقابلہ کر سکتا ہے مگر زہر کی پڑیا کا اس کو کچھ پتا نہیں لگ سکتا.اسی طرح
منافق انسان ہے وہ ایک زہر کی پڑیا کی طرح جس کو انسان نہیں جانتا کہ میرے کھانے میں ملی
ہوتی ہے.وہ کہتے ہیں کہ ہم مصلح ہیں اور ہم صلح جو اور صلح گن ہیں اور ہم نے دونوں فریق سے صلح
رکھی ہوئی ہے.فسادی تو تم ہو کہ خواہ مخواہ ایک جماعت کو الگ کر کے لوگوں سے لڑائی کرتے
ہو.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ سخت مفسد ہیں.یہ آپس میں لڑائی اور فساد ڈلواتے ہیں اور پھر دونوں
فریق سے صلح رکھنے کے لئے ان کو طرح طرح کے حیلے کرنے پڑتے ہیں.مخالفوں کے پاس
گئے تو مسلمانوں کی باتیں ان کو بتلاتے رہے اور جب مسلمانوں کے پاس آئے تو مخالفوں کی
باتیں ان کو بتانی پڑتی ہیں.اور اگر وہ ایسا نہ کریں اور ہر ایک فریق کے سامنے اس کی خیر خواہی
کا اقرار نہ کریں تو صلح کس طرح رکھ سکیں اس لئے ان کو ایک فریق کی بات ضرور دوسرے
فریق کے سامنے ظاہر کرنی پڑتی ہے.جو دونوں گروہوں سے تعلق رکھنا چاہے ضرور ہے کہ وہ
آپس میں فساد بھی ڈلوا دے اور آخر کار پھر ان کو اس بات کا نتیجہ بھگتنا پڑتا ہے.ان کو بیعت
کے لئے کہا جاوے تو کہتے ہیں یہ احمق ہیں ہم جب مانتے ہیں تو بیعت کرنے کی کیا ضرورت
ہے صرف مانناہی کافی ہے.سُفَهَاء - سفہ“.عربی میں بکھیرنے کو کہتے ہیں.جو چیز بکھر
جائے وہ کمزور ہو جاتی ہے.وہ کہتے ہیں کہ یہ سفیہ ہیں.انہوں نے اپنے مال، اپنے گھر بار
اور رشتہ داروں کو چھوڑ دیا.ہم نے دیکھو اپنا مال بچایا ہوا ہے.یہ سُفَهَاء ہیں، دیکھو انہوں نے
اپنے مالوں کی حفاظت نہ کی.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہی سُفَهَاء ہیں اور یہی کمزور ہیں.مومن
بڑھ جاویں گے اور کامیاب ہوں گے.281
Page 290
یہاں قرآن کریم نے صاف صاف فرما دیا ہے کہ وہ مومن نہیں ہیں بلکہ کفار میں شامل ہیں
وَإِذَا خَلَوْا إِلى شَیطِینِهِمْ.دیکھو شیاطین کی نسبت ان کی طرف کی.وہ باتیں بنا بنا کر ان کو
خوش رکھنا چاہتے ہیں.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے.اللهُ يَسْتَهْزِی: ہم.عربی کا قاعدہ ہے کہ کسی
کے جرم اور اس جرم کی سزا کا ایک ہی لفظ ہوتا ہے.اللہ تعالیٰ ان کی ہنسی کی ان کو خوب
سزا دے گا اور انہیں ان کی شرارت کا مزا چکھائے گا.اور ان کو برا بدلہ ملے گا.ان کی تجارت
بری ہے.وہ ہدایت یافتہ نہ ہوئے.( خطبات محمود سال 1914 ، صفحہ 22 تا 36 )
حضرت خلیفہ المسیح الثانی نے خطبہ جمعہ فرمودہ 11 جولائی 1919ء میں سورہ بقرہ کی
ابتدائی آیات پڑھ کر فرمایا:...میرے پاس مختلف جگہوں سے اس قسم کے خطوط آئے ہیں جن میں لکھا ہے کہ چونکہ
ہمارا فلاں سے جھگڑا ہے اس لئے ہم فلاں جگہ نماز پڑھنے کے لئے نہیں جائیں گے اور بعض
کے متعلق دوسروں نے لکھا ہے کہ وہ باجماعت نماز پڑھنے کے لئے اس لئے نہیں آتے کہ
فلاں سے ان
کا جھگڑا ہے...اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں قرآن کریم میں نماز کے لئے حکم بیان
فرمایا ہے وہاں کثرت کے ساتھ قیام صلوۃ اور حفاظت صلوۃ فرمایا ہے.صرف نماز پڑھنے کا لفظ
بہت کم جگہ آیا ہے.اور وہ بھی حکم کے طور پر نہیں.جہاں احکام کا ذکر ہے وہاں اقامت کا لفظ
ساتھ رکھا گیا ہے اور اقامت صلوۃ کے معنے یہ ہیں کہ نماز کو اس کی تمام شرائط کے ساتھ
پڑھا جائے.اقامت کا لفظ عام ہے اور جب کسی امر کی تکمیل ہو جائے تو اس کے متعلق اقامت
کا لفظ بولتے ہیں.مثلاً تجارت ہے.جب کسی ملک کی تجارت پورے زور پر نہ ہو تو اس کی
نسبت کہتے ہیں کہ فلاں ملک کی تجارت بیٹھ گئی اور اگر پورے زور پر ہو تو کہتے ہیں کہ فلاں ملک
کی تجارت کھڑی ہے.اس طرح دوسرے سب امور جب تکمیل کو پہنچ جائیں تو ان کے متعلق
اقامت کا لفظ بولتے ہیں اور جب ان میں کمزوری پیدا ہو تو بیٹھ گئے کہتے ہیں.اس لئے نماز کی
اقامت کے یہ معنی ہوئے کہ اس کو تمام شرائط کے ساتھ ادا کیا جائے اور یہی وہ بات ہے جس کا
قرآن کریم میں حکم دیا گیا ہے.اور یہی وہ چیز ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس
282
Page 291
سے انسان مومن بنتا ہے اور یہی وہ ذریعہ ہے جس سے اللہ کا فضل نازل ہوتا ہے.دیکھو یہی
آیت جو میں نے پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے.ذالِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ
هُدًى لِلْمُتَّقِین.یہ ایسی کتاب ہے.جس میں کوئی شک نہیں ہے.یعنی اس میں ایسی تعلیم
ہے جو ہر ایک شک اور شبہ کو مٹانے والی ہے.اس کے اختیار کرنے سے
کسی قسم کا شک وشبہ
نہیں رہتا.یہ متقیوں کے لئے ہدایت ہے.انہیں ایک سیدھا رستہ دکھاتی ، ایک نئے جہان
میں لے جاتی اور ان پر روحانیت کا دروازہ کھول دیتی ہے.اس سے آگے بتایا کہ متقی کون
ہوتا ہے ؟ فرمایا: الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ
يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ي
شرطیں جب کسی میں پائی جائیں تو وہ متقی ہوتا ہے.اور جب یہ شرطیں پائی جاتی ہیں تب قرآن
روحانیت کی طرف راہ نمائی کرتا ہے.وہ شرطیں یہ ہیں : (1) ایمان بالغیب (2) اقامتِ
نماز (3) جو کچھ خدا نے دیا ہو اس میں سے خرچ کرنا (4) رسول کریم پر اور آپ سے پہلے
نبیوں پر جو کچھ اترا اور جو آئندہ نازل ہوگا اس پر ایمان لانا.ان شرطوں کو جو انسان
پورا کر لیتا ہے اس پر روحانیت کا دروازہ کھل جاتا ہے.لیکن جو ان کو اس طرح پورا نہیں کرتے
ہیں جس طرح ان کے پورا کرنے کا حق ہے انہیں قرآن ہدایت نہیں کرتا.یہی وجہ ہے کہ
بہت لوگ قرآن پڑھتے ہیں مگر کہتے ہیں ہمیں کچھ فائدہ نہیں ہوتا.بات دراصل یہی ہے کہ
قرآن اسی وقت ہدایت کرتا ہے جبکہ یہ شرائط پوری ہوں.ان شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ نماز کو قائم کرنا اور جماعت کے ساتھ ادا کرنا.بعض
لوگ بے علمی اور نا واقفیت کی وجہ سے کہتے ہیں کہ جمعہ کی نماز باجماعت پڑھنا فرض ہے.حالا نکہ بات یہ ہے کہ جمعہ کی نماز ایسی ہی فرض ہے جیسا کہ ساری نمازیں.قرآن کریم میں
جمعہ کی نماز کا اگر ایک جگہ ذکر آیا ہے تو روزانہ نمازوں کا ذکر متعد دجگہ آیا ہے.پس جمعہ کی نماز
دوسری نمازوں سے زیادہ فرض نہیں ہے لیکن لوگ لاعلمی کی وجہ سے سمجھتے نہیں اور صرف جمعہ
کی نماز باجماعت ادا کرنا فرض جانتے ہیں.حالانکہ قرآن کریم میں جہاں جہاں آقِیمُو الصَّلوةَ
کا ذکر آیا ہے وہاں نماز با جماعت کا ہی حکم ہے.حتی کہ ایک صحابی کے متعلق لکھا ہے کہ وہ
283
Page 292
کہتے نماز ہوتی ہی نہیں جب تک کہ باجماعت نہ ہو.مگر ہمیں صحابہ کے قول پر ہی اکتفاء کرنے
کی ضرورت نہیں.رسول کریم علال لا علم کے اقوال بھی ایسے ہی ملتے ہیں.چنانچہ فرماتے ہیں.جولوگ عشاء اور صبح کی نماز باجماعت پڑھنے کے لئے مسجد میں نہیں آتے میرا دل چاہتا ہے کہ
میں اپنی جگہ کسی اور کو نماز پڑھانے کے لئے کھڑا کر دوں اور اپنے ساتھ اور آدمیوں کو لے کران
کے سر پر ایندھن رکھ کر ان لوگوں کے گھروں میں جاؤں اور آدمیوں سمیت ان کے گھروں کو
جلا کر راکھ کر دوں.( بخاری و مسلم بحوالہ مشکوۃ کتاب الصلوة في الجماعة وفضلها ).دیکھو رسول كريم عليم
جیسا رحیم انسان جو کسی کی ادنیٰ سے ادنی تکلیف کو بھی نہیں دیکھ سکتا تھا اور جس کے متعلق
خدا تعالیٰ فرماتا ہے رحمةً لِلعلمين (الانبیاء 108 ) وہ جب یہ کہتا ہے کہ جولوگ مسجد میں
نماز پڑھنے کے لئے نہیں آتے ان کو مع اُن کے گھروں کے جلا دوں تو اس سے یہ نہیں
سمجھا جاسکتا کہ باجماعت نماز پڑھنا کوئی معمولی بات ہے.بلکہ فرضوں میں سے بہت
بڑا فرض ہے جس کے ادا نہ کرنے کے متعلق رسول کریم مبلی نے اس قدر شدت سے نفرت
کا اظہار کیا ہے.پس جو لوگ اس کو پورا نہیں کرتے انہیں سوچنا چاہئے کہ وہ رسول کریم
ام کی کس قدر ناراضگی کا بار اپنے اوپر اٹھاتے ہیں.انہیں خوب اچھی طرح سن لینا چاہیئے
کہ کسی کی لڑائی اور کسی سے جھگڑا اس فرض کی ادائیگی میں ہر گز روک نہیں ہوسکتا.اگر وہ زید وبکر
کے لئے نماز پڑھتے ہیں تو ان سے لڑائی ہونے کی وجہ سے چھوڑ سکتے ہیں لیکن اگر خدا کے لئے
پڑھتے ہیں تو پھر کون ہے جو کہہ سکتا ہے کہ چونکہ خدا سے میری لڑائی ہے اس لئے میں نماز
نہیں پڑھتا.اگر اس سے کسی کی لڑائی ہے تو وہ نہ پڑھے.اور اگر نہیں تو زید و بکر کی لڑائی کی
وجہ سے خدا کی نماز کو کیوں ترک کرتا ہے.میرے نزدیک وہ شخص جونماز باجماعت پڑھنے میں
سستی کرتا ہے کسی قسم کی روحانی ترقی حاصل نہیں کرسکتا.کیونکہ یہ نہایت ضروری رُکن اسلام
ہے.اور ایسا ضروری ہے کہ رسول کریم علیہ فرماتے ہیں کہ جو اس کو ادا نہیں کرتا میراجی
چاہتا ہے کہ میں اس کو مع اس کے گھر کے جلا دوں.بعض لوگوں نے صرف عشاء اور صبح کی نماز
باجماعت نہ ادا کرنے والوں کے متعلق اسے سمجھا ہے.لیکن اصل میں اس میں ساری نمازیں
284
Page 293
آجاتی ہیں کیونکہ یہی دونوں نمازیں پڑھنا مشکل ہوتی ہیں.جب ان کے متعلق فرما دیا تو باقی
نمازیں خود بخود اس کے نیچے آگئیں.تو نماز باجماعت پڑھنا ہر ایک مسلمان پر بہت بڑا فرض
اور ایک اہم ذمہ داری ہے.جو اس سے جی چراتا ہے خواہ زید و بکر کی لڑائی سے یا کسی اور وجہ
سے وہ قطعاً اس قابل نہیں ہے کہ مومن احمدی کہلا سکے کیونکہ وہ خدا کا مجرم ہے اور میرے
نزدیک اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی بے وقوف اور کم عقل نہیں ہو سکتا جو انسان سے لڑ کر
خدا سے لڑائی شروع کر دے.قاعدہ تو یہ ہے کہ جب کسی سے لڑائی ہو تو دوسروں کی ہمدردی
حاصل کی جاتی ہے.دیکھو گورنمنٹ برطانیہ کی جب جرمنی سے لڑائی شروع ہوئی تو باوجود اس
کے کہ بہت بڑی حکومت ہے چھوٹی چھوٹی سلطنتوں کو بھی اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرتی
رہی ہے.تو چونکہ لڑائی کے وقت انسان زیادہ دوستوں اور مددگاروں کا حاجت مند ہوتا ہے اس
لئے اگر کسی کی کسی سے لڑائی ہو تو اس کو ضرورت ہے کہ اپنے زیادہ دوست بنائے اور خدا سے
بڑھ کر اور کون دوست ہوسکتا ہے.پس اس وقت جب کہ لڑائی نہ تھی ،امن تھا اگر خدا کو
دوست بنانے کی کوشش کی جاتی تھی تو اب جبکہ ڈر ہے کہ دوسرے سے نقصان اٹھائے
بہت زیادہ ضرورت ہے کہ خدا کو اپنا دوست اور مددگار بنائے.اور یہ وقت ہے کہ وہ اس سے
صلح کرے، نہ کہ لڑائی لیکن جو کسی سے لڑائی ہونے کی وجہ سے نماز کو ترک کر دیتا ہے اس کی
مثال ایسی ہی ہے جیسا کہ کسی کے گھر جب ڈاکہ پڑے تو وہ لوگوں کو مدد کے لئے بلانے کی
بجائے انہیں پتھر مارنا شروع کر دے.اس کا نتیجہ کیا ہوگا ؟ یہی کہ ڈا کو باہر سے اس پر حملہ آور
ہوں گے اور ہمسائے اندر سے اس کو نقصان پہنچائیں گے.پس جو شخص کسی سے لڑائی کی وجہ
سے نماز باجماعت پڑھنا چھوڑتا ہے وہ یقینی طور اپنی تباہی کا موجب بنتا ہے.ایک نادان کا لطیفہ مشہور ہے مگر میرے نزدیک نماز چھوڑنے والا اس سے بھی زیادہ نادان
اور بیوقوف ہے.کہتے ہیں کسی سے کوئی شخص برتن مانگ کر لے گیا تھا.کچھ دن تک جواس
نے واپس نہ دیا تو ایک دن وہ خود لینے گیا اور جا کر دیکھا کہ وہ اس کے برتن میں سالن ڈال
کر کھا رہا ہے.یہ دیکھ کر کہنے لگا کہ تو نے میرے برتن میں سالن ڈال کر کھایا ہے، میں تیرے
285
Page 294
برتن میں پاخانہ ڈال کر کھاؤں گا.تو یہ سزا دینے کا عجیب طریق ہے کہ چونکہ فلاں سے میری لڑائی
ہے.اس لئے میں نے نماز باجماعت پڑھنا چھوڑ دی ہے.جو شخص اس طرح کرتا ہے اس
نے اپنے دشمن کو اپنے اوپر خود غالب کر لیا.کیونکہ اس کے دشمن نے ایک تو اسے اپنے پاس
سے دور کر دیا اور دوسرے خدا سے بھی دور کر دیا.پس اس طرح اس نے اپنے دشمن کو نیچا نہیں
دکھایا بلکہ خود نقصان اٹھایا ہے.یہ سخت جہالت اور نادانی ہے کیونکہ کسی سے دشمنی کی وجہ سے
نماز چھوڑنے کا ہر گز حکم نہیں.نماز باجماعت ادا کرنے کا خدا کا حکم ہے محمد بلا نیکی کا حکم ہے
اور اس شریعت کا حکم ہے جس کے بعد کوئی نئی شریعت نہیں آئے گی اور اس شریعت کا حکم
ہے جس کا ایک شعشہ بھی بدل نہیں سکتا.پس یہ مت سمجھو کہ احمدی کہلانے سے خدا کے حکموں
کو توڑنے کی اجازت ہوگئی ہے بلکہ پہلے کی نسبت بہت زیادہ فرض ہو گیا کہ ہر ایک حکم
پر پورے طور پر عمل کرو.اس لئے عقل اور دانائی سے کام لو اور خدا کے حکموں کومت توڑو کیونکہ
اب تم نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر دین کو دنیا پر مقدم کرنے کا عہد
کیا ہے اور شریعت کو اچھی طرح سمجھا ہے.اب اگر اس کے خلاف کرو گے تو دوسروں کی
نسبت خدا کے غضب کے زیادہ مستوجب بنو گے.خدا تعالیٰ تمہیں توفیق دے کہ شریعت کے
تمام احکام کی تم قدر کرو اور ان پر عمل پیرا ہو.( خطبہ جمعہ فرمودہ 11 جولائی 1919ء - خطبات محمود ( سال 1919 ء ) صفحہ 262 تا 268)
حضرت خلیفہ المسیح الثالث رحمہ اللہ فرماتے ہیں:
میرے دل میں یہ خواہش شدت سے پیدا کی گئی ہے کہ قرآن کریم کی سورۃ بقرہ کی ابتدائی
سترہ آیتیں جن کی میں نے ابھی تلاوت کی ہے.ہر احمدی کو یاد ہونی چاہئیں اور ان کے معانی
بھی آنے چاہئیں اور جس حد تک ممکن ہو ان
کی تفسیر بھی آنی چاہیے اور پھر ہمیشہ دماغ میں وہ
مستحضر بھی رہنی چاہیے....مجھے...امید ہے کہ آپ میری روح کی گہرائی سے پیدا ہونے
والے اس مطالبہ پر لبیک کہتے ہوئے ان آیات کو زبانی یاد کرنے کا اہتمام کریں گے.مرد بھی
286
Page 295
یاد کریں گے عورتیں بھی یاد کریں گی.چھوٹے بڑے سب ان سترہ آیات کو آز بر کرلیں
گے....اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں جو مضمون بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت نبی اکرم
افضل الرسل ہیں.آپ انسان کامل ہیں.آپ پر کامل شریعت نازل ہوئی.آپ خاتم النبیین
کے لقب سے سرفراز ہوئے.آپ نے اللہ تعالیٰ کی صفات کا جو جلوہ اپنے وجود میں دکھایا اس
کے نتیجہ میں یہ دنیا تین گروہوں میں بٹ جائے گی.ایک گروہ وہ ہے جو ایمان لائے گا.فرمایا ان کی بنیادی خصوصیات یہ ہوں گی کہ وہ اپنی تمام
جسمانی اور ذہنی قوتوں اور صلاحیتوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لئے قربان کر دیں
گے.اپنی اخلاقی اور روحانی قوتوں کو انوار الہیہ سے منور بنا کر اس سے ساری دنیا کومستفید
کرنے کی کوشش میں لگے رہیں گے اور ان کی تیسری بنیادی خصوصیت یہ بتائی کہ اس دنیا
میں آئندہ ظہور پذیر ہونے والے واقعات پر مشتمل جو پیش خبریاں دی گئی ہیں اور بشارتیں دی
گئی ہیں.وہ ان پر اس طرح ایمان لاتے ہیں گویا کہ یہ باتیں پوری ہو چکی ہیں.انہیں اللہ
تعالیٰ کی صفات، اس کی قوتوں اور اس کی طاقتوں پر یقین ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسی ہی بات
ہے جیسے کہ ہو چکی ہو اور اگر اس کے راستہ میں کوئی روک پیدا ہوتو وہ اس روک کو دور کرنے کی
کوشش کرتے ہیں اور کسی قربانی سے گریز نہیں کرتے.ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی
تقدیر ہے ضرور ہو کر رہے گی.اگر کوئی روک پیدا ہوئی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ہماری
کوئی آزمائش مقصود ہے لہذا ہمیں اس آزمائش میں پورا اترنا چاہیے تا کہ ہمیں ثواب اور اجر
کے زیادہ مواقع عطا ہوں.وہ اس یقین پر بھی قائم ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے
جسمانی اور روحانی ترقیات کے لامحدود دروازے کھول رکھے ہیں اور ان کی یہ بھی خصوصیت ہے
که روحانی رفعتوں کو حاصل کرتے ہوئے کسی ایک مقام پر جا کر رک نہیں جاتے یا اسی کو کافی
سمجھ کر وہیں بیٹھ نہیں جاتے بلکہ ان کی زندگی غیر محدود ترقیات کے حصول میں ایک غیر محدود
287
Page 296
جدو جہد میں رواں دواں رہتی ہے.غرض سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس ہدایت یافتہ گروہ کی
بنیادی خصوصیات پر روشنی ڈالی ہے.اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک دوسرا گروہ منکرین اسلام کا گروہ ہے اور ان کے
انکار کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو صداقت حقہ کے قبول کرنے اور دلی بشاشت کے
ساتھ قربانیاں دینے کی جو قابلیتیں اور قوتیں عطا کی تھیں یہ ان کو کھو بیٹھے ہیں.اللہ تعالیٰ نے
ان کے دل میں روحانی اثر کے قبول کرنے کی صلاحیت بخشی تھی جس سے یہ بہت کچھ سیکھ سکتے
تھے لیکن ان کے دل پتھر ہو گئے اور اپنی فطرتی حالت میں نہیں رہے جو رقت کی اور رجوع کی
اور تو بہ کی اور عاجزی کی حالت ہے اور چونکہ ان کے دل پتھر ہونے کی وجہ سے اپنی فطری
حالت پر نہیں رہے اس لئے فطرتی دینی اعمال بجالانے کے قابل نہیں رہے.پھر اللہ تعالیٰ
نے دل کی بہت سی دوسری امراض بتائیں اور ان کے علاج بھی بتائے.پھر اللہ تعالیٰ فرماتا
ہے کہ ان کے اندر ایک چیز یہ بھی نظر آتی ہے کہ ہم نے انہیں سننے کے لئے کان دیے تھے اور
سماع سے ہماری مراد یہ تھی کہ جب صوتی لہریں ہوا کے دوش پر ان کے کانوں تک پہنچیں تو پھر
آگے ان کے اثرات ذہن پر پڑیں جس سے دل بھی متاثر ہوں کیونکہ قبول ہدایت کا ایک بڑا
ذریعہ دل ہی ہے.انسان جب نیکی کی باتیں غور سے سنتا ہے تو اس کا ذہن تدبر سے کام لیتے
ہوئے ان کے اثرات کو دل کی طرف منتقل کر دیتا ہے جس کے نتیجہ میں دل کے اندر ایک ایسا
انقلاب اور ایک ایسا تغیر رونما ہوتا ہے کہ انسان قبول ہدایت کے لئے تیار ہو جاتا ہے لیکن
انہوں نے اپنی بداعمالیوں کے نتیجہ میں کانوں پر مہر لگا دی ہے.کوئی آواز ان کے کانوں میں
پڑتی ہی نہیں.صوتی لہریں ان کے کانوں سے ٹکراتی اور واپس ہو جاتی ہیں یا ایک کان میں گھستی
ہیں اور دوسرے کان سے نکل جاتی ہیں.پھر ان کو آنکھیں اس لئے دی تھیں کہ وہ اس دنیا میں
خدائے حی و قیوم کے قادرا نہ تصرفات کا مشاہدہ کرتے اور اس سے عبرت حاصل کرتے.تاریخ عالم پر نگاہ ڈالتے ،مختلف آسمانی کتابوں کو غور سے پڑھتے اور پھر فکر وتدبر سے کام لیتے تو
288
Page 297
انہیں یہ معلوم ہوتا کہ دنیا میں جب سے انبیاء علیہم السلام کے ذریعہ رشد و ہدایت کا سلسلہ جاری
ہوا ہے اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے ساتھ یہ سلوک رہا ہے کہ جب بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی
آواز پر لبیک کہی اس کی طرف سے نازل ہونے والی ہدایت کو قبول کیا اس کی بارگاہ پر جھک
گئے اور اس کی راہ میں قربانیوں سے دریغ نہ کیا.اللہ تعالیٰ نے ان پر کس طرح اپنے انعامات
نازل کئے اور انہیں کس طرح اپنے فضلوں کا وارث بنایا.مگر جن لوگوں نے خدا تعالی کی اس
آواز پر کان نہ دھرے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی ہدایت کو ٹھکرا دیا اور اس کی قدر نہ کی
وہ کس طرح اللہ تعالیٰ کے غضب کے بھنور میں پھنس کر ہلاکت سے دو چار ہوئے.اللہ تعالیٰ
فرماتا ہے ان منکرینِ اسلام کی تو یہ حالت ہے کہ گویا ان کی آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے
ہیں حالانکہ فطرتی لحاظ سے ان کی آنکھوں پر کوئی غلاف نہیں تھا.یہ تو انہوں نے خود اپنی
آنکھوں پر چڑھا لیا ہے.ان کی حالت اس گھوڑے یا گدھے کی مانند ہے جس کی آنکھوں پر
پردہ ڈال دیتے ہیں کہ چلتے وقت کسی چیز کے خوف سے ڈر نہ جائے.پس انہوں نے بھی اس
خوف سے کہ کہیں روحانیت کی کوئی جھلک ان کی آنکھوں میں نہ پڑ جائے ( جو دنیوی عارضی
مسرتوں سے ان کو دُور لے جائے ) اپنی آنکھوں پر غلاف چڑھالئے ہیں جس کی وجہ سے یہ
حسن و احسان کے روحانی جلوے دیکھنے سے قاصر ہیں.بہر حال سورۃ بقرہ کی ان ابتدائی سترہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے منکرین کا ذکر کر کے ان کی
جسمانی کیفیات اور ان کے روحانی امراض کی طرف متوجہ کرتے ہوئے سامان عبرت مہیا
فرمایا.پھر ان
کو جھنجھوڑ کر یہ انتباہ فرمایا کہ اگر تمہاری حالت یہی رہی تو تم حق کو ہر گز قبول نہیں
کر سکتے.تم قبولِ حق کی توفیق صرف اسی صورت میں پاسکتے ہو کہ تمہاری روحانی اور اخلاقی
کیفیت یہ نہ ہو کہ ہمارے اس عظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈرانا یا نہ ڈرانا تمہارے لئے برابر
ہو.چاہیے کہ اس کا ڈرانا تمہارے دلوں پر اثر انداز ہو.جب تک تمہارے اندر یہ تبدیلی رونما
نہیں ہوتی جب تک وہ مہر میں جو تم نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے قلوب اور اپنے کانوں پر لگالی
289
Page 298
ہیں ان کو تم توڑ نہ دو اور ہم نے آسمانی مؤثرات کو قبول کر لینے کے لئے تمہارے دل میں جو
کھڑ کیاں بنا رکھی ہیں ان کو تم کھول نہ دو.جب تک تم ان غلافوں اور ان پر دوں کو جنہیں تم نے
اپنی آنکھوں پر ڈال لیا ہے جو اللہ تعالیٰ کے نور سے اپنے آپ کو چھپانے کے لئے اور اللہ تعالیٰ
کے نور کے جلووں سے اپنے آپ کو بچانے کے لئے خود ہی تم نے اپنی آنکھوں پر پٹی کے طور
پر باندھ رکھے ہیں تم ان کو ہٹا نہ دو، اس وقت تک تمہاری یہ حالت مبدل بہ اسلام نہیں ہوسکتی
اور اللہ تعالیٰ کی توجہ کو تم حاصل نہیں کر سکتے.تم جب تک اپنی یہ حالت نہیں بدلتے خدا تعالیٰ
سے ڈورو مہجور رہو گے.دنیا کی جھوٹی اور عارضی لذت سے تم لطف اندوز تو ہو سکتے ہولیکن اگر تمہاری
یہی حالت رہے تو تم اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے پیار کی حقیقی اور سچی لذت اور ابدی سرور کو کبھی
حاصل نہیں کر سکتے.پس جب تک منکرین دین کی حالت نہیں بدلتی.اس وقت تک قرآن کریم کی
تعلیم یا حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوگا.پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا.ایک اور گروہ بھی دنیا میں پیدا ہوگا اور یہ ان لوگوں کا
گروہ ہے جو کہتے تو یہ ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت پر ایمان لائے لیکن درحقیقت وہ ایمان نہیں
لاتے.ان کا یہ دعویٰ ایمان سراسر جھوٹا ہوتا ہے.پہلے دو گروہوں کا ذکر نسبتا مختصر الفاظ میں
فرمایا کیونکہ اس متن اور مضمون میں ان دو گروہوں کے بارے میں زیادہ کہنے کی ضرورت اس
لئے بھی نہیں تھی کہ ان دونوں گروہوں کی خصوصیات اور کیفیات ظاہر و باہر ہوتی ہیں مگر جس گروہ کا
ذكر وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ کے الفاظ سے شروع ہوتا ہے اس کے متعلق نسبتاً زیادہ باتیں
بیان کرنے کی ضرورت تھی کیونکہ یہ گروہ مار آستین بن کر اندر ہی اندر جماعت کے اجتماعی جسم کو
ڈستا رہتا ہے.منکرینِ اسلام ظاہری طور پر باہر سے علی الاعلان حملہ آور ہوتے ہیں اور مومن
بندے اپنے اپنے اخلاص کے مطابق اللہ تعالیٰ پر توکل رکھتے ہوئے اس کے سامنے
سینہ سپر رہتے ہیں.وہ ہر وقت چوکس اور بیدار رہ کر اس کے شب خون سے محفوظ رہتے ہیں.کیونکہ ایک مومن جس طرح دن کو بیدار اور باخبر رہتا ہے اسی طرح وہ شب بیدار بھی ہوتا ہے
290
Page 299
کیونکہ جولوگ رات کو سو جاتے ہیں دشمن ان پر تو شب خون مارتا اور بے خبری میں ان کو شدید
نقصان پہنچاتا ہے لیکن وہ جو دن کو بھی ہوشیار ہو اور جو راتیں بھی خدا تعالیٰ کی حمد اور اس کی شنا
کرتے ہوئے گزارتا ہو شیطان اس پر شب خون مارنے کی جرات نہیں کر سکتا.اس لئے
منکرین اسلام کی بعض بنیادی باتوں کے اظہار پر اکتفا فرماتے ہوئے یہ سبق دیا کہ منکرین کی
بیماریوں
کی تشخیص کو میں نے آسان کر دیا ہے.اس لئے میری ان ہدایتوں کی روشنی میں اپنی دلی
ہمدردی اور غم خواری سے ان کے علاج میں کوشاں رہنا تمہارا فرض ہے.لیکن یہ جو تیسرا گروہ
ہے یہ ایک مومن کے لباس میں مگر ایک فتنہ گر کی حیثیت میں امت مسلمہ میں داخل ہوتا ہے
اور اندر ہی اندر مفسدانہ سرگرمیوں میں مصروف رہتا ہے اس لئے اس بات کی زیادہ ضرورت تھی
کہ اللہ تعالیٰ اس گروہ کی برائیوں اور بد خصلتوں کے متعلق زیادہ تفصیل سے بیان فرمائے.چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جو باتیں اس گروہ کے متعلق ان چند آیات میں بیان فرمائی ہیں وہ بنیادی
حیثیت کی حامل ہیں.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ اور مومنوں کو دھوکا دینا چاہتے ہیں....فرماتا ہے کہ جس طرح یہ لوگ مجھے دھوکا نہیں دے سکتے کیونکہ میں علام الغیوب ہوں، میرے علم
نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، مجھ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، مجھ پر کبھی غفلت طاری نہیں
ہوتی غرض اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی صفات کی مالک ہے کہ اسے کوئی دھوکا نہیں دے سکتا
کیونکہ اس سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے.لاریب یہ خدا تعالیٰ کی بلندشان ہے لیکن اللہ
تعالیٰ نے یہاں یہ بھی فرمایا ہے کہ اسی طرح میرے مومن بندوں پر بھی منافقت کی کوئی چال
کارگر نہیں ہوسکتی.منافق انہیں بھی کوئی دھوکا نہیں دے سکتے.اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن
بندے کو کتنا بڑا مقام عطا کیا ہے کہ اس کو بھی اپنے ساتھ.( اس بات میں کہ اللہ تعالیٰ اور اس
کے مومن بندوں کو منافق دھوکا نہیں دے سکتے یہاں منافق کے دھوکے سے بچنے میں اللہ
تعالیٰ نے مومن بندے کو بھی اپنے ساتھ شامل کیا.) یہ در حقیقت بڑے ہی پیار اور اعتماد کا
291
Page 300
اظہار ہے مگر اس کے ساتھ ہی ہم پر بڑی بھاری ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں کیونکہ بالواسطہ
طور پر اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا منشاء یہ ہے کہ اس کے مومن بندے بھی
اس کی طرح ہر وقت چوکس اور بیدار رہیں اور اپنے دائرہ عمل میں ہر چیز کا علم حاصل کریں.انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی کوئی چیز ان سے پوشیدہ نہ رہے.اب مثلاً میر اعلم جو ہے
اس کا ایک حصہ ایک لحاظ سے دراصل آپ کا ہی علم ہے کیونکہ مجھے کراچی کی بیدار اور چوکس
جماعت بھی اطلاع بھجوا رہی ہے، مجھے راولپنڈی کی بیدار اور چوکس جماعت بھی اطلاع بھیجوا
رہی ہے، مجھے پشاور کی بیدار اور ہوشیار جماعت بھی اطلاع دے رہی ہے غرض ہر جگہ سے
جہاں بھی ہماری جماعت قائم ہے وہاں سے مجھے اطلاع مل رہی ہے اور چونکہ میرا اور آپ کا
وجود ایک ہی ہے.اللہ کے فضل سے آپ میری آنکھیں ہیں جن کے ذریعہ سے میں دیکھتا اور
علم حاصل کرتا ہوں آپ میرے کان ہیں جن کے ذریعہ سے میں سنتا اور حالات کی روش کو
محسوس کرتا ہوں.چنانچہ آپ کی فراست اور میری فراست دراصل ایک ہی تصویر کے دورخ
یا ایک ہی پیالے کے مختلف اطراف ہیں.پس اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرح مجھے کوئی منافق دھوکا نہیں دے سکتا اس طرح
میرے مومن بندے کی بھی یہی شان ہے اسے بھی کوئی منافق دھوکا نہیں دے سکتا.بڑے ہی
پیار کا اظہار ہے لیکن ساتھ ہی بڑا بے چین اور پریشان کر دینے والا بیان بھی ہے.پس اللہ
تعالی سے دعا ہونی چاہیے کہ یہاں جس اعتماد کا اظہار کیا گیا ہے ہم اس اعتماد پر پورا اتر نے
والے ثابت ہوں.فرمایا ان منافقوں کی دوسری علامت یہ ہے کہ ان کے دل میں مرض پیدا ہو چکا ہے اور یہ
خود اپنے علاج کی طرف متوجہ نہیں ہوتے اس لئے خدا تعالیٰ کی صفات کا جو عام جلوہ ہے کہ جیسا
کوئی بندہ ہوتا ہے اسی کے مطابق اس سے اس کا سلوک بھی ہوتا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ
مرض گھٹتا نہیں بلکہ فطرتی تقاضوں کی غلط روش سے ان کا مرض بڑھتا ہی چلا جاتا ہے.چنانچہ
292
Page 301
قرآن کریم نے امراض قلوب پر متعدد جگہ روشنی ڈالی ہے.دل کی ایک مرض نہیں ہوتی بلکہ
متعدد امراض ہیں جس طرح جسم کی بھی ایک مرض نہیں انسان مختلف قسم کی غلطیاں کرتا رہتا
ہے.صبح ایک قسم کی غلطی کر بیٹھتا ہے اور شام کو دوسری قسم کی غلطی کا مرتکب بن جاتا ہے ہر
مرض کا تعلق انسان کے کسی نہ کسی غلط اقدام سے ہے انسان کی کسی نہ کسی غلط روش کے نتیجہ
میں مرض لاحق ہوتی ہے اور ان آیات میں اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے....بہر حال منافق کی دوسری علامت یہ بتائی کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے مومن بندوں کو تو دھوکا دینا
چاہتا ہے مگر اس کا اپنا یہ حال ہے کہ ہر قسم کی روحانی بیماریوں میں مبتلا ہے.منافقت نے اس کے
درخت وجود کو پراگندہ کر کے رکھ دیا ہے اس کا جسم ایک آتشک زدہ کے جسم کے مشابہ ہے.جس
طرح آتشک وغیرہ کے مریض کے اعضاء گلنے سڑنے لگ جاتے ہیں اس صورت میں وہ انسانی
جسم کہلانے کا مستحق نہیں رہتا بلکہ عفونت اور گندگی کے ایک لوتھڑے کا مصداق بن جاتا ہے اسی
طرح منافق بھی روحانی طور پر گندگی اور ناپاکیزگی اور عدم طہارت کی وجہ سے ایک لوتھڑا ہی ہوتا
ہے وہ حقیقی معنوں میں انسان کہلانے کا مستحق نہیں ہوتا حالانکہ وہ انسان کے زمرہ میں شامل ہے اور
انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے لامحدود روحانی ترقیات کے لئے پیدا کیا تھا.اللہ تعالیٰ نے اس گروہ کی تیسری بیماری یا کمزوری یہ بتائی ہے کہ یہ اپنے آپ کو مصلح سمجھتے
ہیں یعنی یا تو اپنی جہالت کے نتیجہ میں خود ہی مصلح بنے پھرتے ہیں اور یا پھر شرارت کی نیت
سے ایک مصلح کا روپ دھار لیتے ہیں.بہر حال وہ ایک مصلح کے لباس میں امت مسلمہ میں
، رہتے ہیں اور اسے اندر ہی اندر سے کھوکھلا کر دینے کے لئے منافقانہ کارروائیوں میں
سرگرداں رہتے ہیں.چنانچہ ہماری تاریخ میں اس قسم کی منافقانہ سرگرمیوں کی ایک نہیں، دو
نہیں.بلکہ بیسیوں مثالیں پائی جاتی ہیں کہ بعض یہودی مسلمان علماء کی شکل میں مسلم معاشرہ
کے جزو بن کر تباہی و بربادی پھیلاتے رہے.سپین میں مسلمانوں کی صدیوں تک حکومت رہی
اور ایک وقت تک ان کے رعب اور ان کے علم و فضل اور ان کے اخلاق فاضلہ نے سارے
293
Page 302
یورپ پر اپنی دھاک بٹھائے رکھی.بڑے بڑے مشہور پادریوں نے سپین میں آ کر مسلمانوں
سے علوم وفنون سیکھے.اگر چہ ظاہری طور پر یا سیاسی لحاظ سے مسلمانوں کا اقتدار سپین کے خطہ ہی
پر تھا لیکن حقیقت میں ان کی حکومت سارے یورپ کے ذہن پر اور سارے یورپ کے دل پر
تھی لیکن بعض یہودی مسلمانان اندلس کی صفوں میں داخل ہوئے اور مسلمانوں کی عبرتناک
تباہی کا باعث بنے.شروع میں اُنہوں نے مسلمانوں سے کتابی علوم سیکھے کیونکہ اسلامی علوم سیکھنے
کے لئے ایمان لانے کی شرط نہیں ہے.اب عام آدمی بھی مسلمان ہوئے بغیر اپنے ذہن اور
حافظہ کی مدد سے اسلامی علوم کے ظاہری حصہ پر حاوی ہوسکتا ہے البتہ کتاب مکنون والے حصے
میں جا کر حقیقی نیک اور ظاہری نیک میں عقل و فکر اور غور تدبر کرنے والے فرق کر لیتے ہیں.بہر حال یہ لوگ دشمنی کی نیت سے اسلام میں داخل ہوئے ظاہری علوم سیکھ کر حضرت مولانا‘
بن بیٹھے اور پھر اندر ہی اندر وہ فتنہ بپا کیا کہ چشم فلک نے شاید ہی پہلے کبھی دیکھا ہو.مگر ایمان
رکھنے والے اللہ تعالیٰ سے محبت کا دم بھرنے والے مسلمانوں نے اُس وقت اپنی اس عظیم
ذمہ داری کو فراموش کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے اعتماد سے فرمایا تھا کہ مجھے اور میرے مومن
بندوں کو یہ منافق دھوکا نہیں دے سکتے.مگر مسلمانان اندلس نے ایسے منافقوں کے فتنوں سے
بچنے کے لئے ہوشیاری اور بیدار مغزی کا ثبوت نہ دیا.دراصل ایک منافق کا ایک بہت بڑا حربہ یہ
ہوتا ہے کہ وہ شیطان بن کر ایک آدمی کے پاس چلا جاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ دیکھو آپ اتنے
نیک اور بزرگ اور یہ اور وہ ہیں اور خلیفہ وقت کتنا ظالم ہے کہ اس نے پبلک میں آپ کو جھاڑ دیا
حالا نکہ آپ
کو تو اللہ تعالیٰ نے بڑی عقل دی ہے آپ بڑے بزرگ ہیں.اگر وہ آدمی بد بخت ہے تو
وہ اس کے دھوکے میں آجاتا ہے.لیکن اگر اس آدمی پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ ہے تو وہ آگے سے
اسے جواب دیتا ہے کہ تم غلطی سے میرے دروازے پر آگئے ہو تمہیں کسی اور طرف جانا چاہیے تھا.مجھے تو یہ پتہ ہے کہ جس طرح خدا تعالی کو کبھی نہ نیند آتی ہے اور نہ کبھی اونگھ اور نہ ہی کبھی اس پر غفلت
طاری ہوتی ہے میں بھی ظلی طور پر خدا تعالیٰ کی ان صفات سے متصف ہونے کی حیثیت میں ہوشیار
294
Page 303
اور بیدار ہوں تم میرے پاس کیا لینے آگئے ہو.ہماری جماعت میں ایسے دس ہیں ، سو دو سو واقعات
سال میں رونما ہو ہی جاتے ہیں.مجھے اطلاع ملتی رہتی ہے.لکھا ہوتا ہے کہ میرے پاس منافق آیا
تھا اور میں نے اسے یہ جواب دیا ہے.لیکن جن پر غفلت طاری ہوتی ہے یا جن کی حالت ایمان اور نفاق کے درمیان ہوتی ہے
دل اور دماغ اور روح میں کچھ روحانی کمزوری ہوتی ہے.جن کو اللہ تعالیٰ نے منافق نہیں قرار
دیا بلکہ فرمایا ہے کہ یہ کمزوری ایمان رکھنے والے ہیں دل کی ساری امراض کو نفاق نہیں کہا
اگر چہ یہ امراض نفاق کا حصہ ضرور ہیں لیکن ان کو گلیۂ نفاق بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ اگر کسی کے
دل میں ایک فیصدی نفاق ہے تو وہ منافق نہ ہوا مگر اس کی حالت خطرہ سے باہر بھی نہیں ہوتی.ایسے شخص کی اصلاح اور تربیت آسانی سے کی جاسکتی ہے.پس منافق مصلح کے لباس میں دوست اور ہمدرد کی حیثیت سے لوگوں کے پاس جاتے اور
ان کے ایمان کے اندر رخنہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں.یہ رخنہ ابتدا میں سوئی کے ناکے
کے برابر ہوتا ہے بظاہر بالکل معمولی سا نظر آتا ہے لیکن اندر سے گند کا ایک لوتھڑا بن جاتا ہے
مثلاً آج کل سیب کا پھل عام ہے آپ نے دیکھا ہوگا بعض کیڑے سیب پر حملہ آور ہوتے ہیں
پ ایک سیب اُٹھائیں اس پر سوئی کے ناکے کے برابر داغ نظر آئے گا اور جب اسے
عولیں گے تو دیکھیں گے کہ اندر موٹی موٹی سونڈیاں پھر رہی ہوں گی حالانکہ اس سیب پر
بظاہر سُوئی کے ناکے سے زیادہ سوراخ نظر نہیں آئے گا.......اللہ تعالی نے ہمیں ان آیات میں یہ بتایا ہے کہ منافق ایک مصلح کے روپ میں تمہارے
سامنے آئے گا جب کبھی وہ تمہارے سامنے اس روپ میں آئے تو ہم تمہیں ایک جواب سکھاتے
ہیں وہ جواب تم اس کو دے دیا کرو تم اس سے کہہ دیا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے.آلا
إنّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ تم اصلاح کا جو بھی جامہ پہنو ہم تمہیں پہچانتے ہیں کیونکہ خدا تعالیٰ کی یہ
آواز ہمارے کانوں میں گونج رہی ہے کہ تم ہی مفسد ہو.تمہارا مصلح کے روپ میں ہمارے
295
Page 304
سامنے آنا ہمیں دھوکا نہیں دے سکتا.منافق کی چوتھی علامت یہ بیان کی گئی ہے کہ منافق لوگ اپنے آپ کو بڑا عقل مند اور ہوشیار
سمجھتے ہیں اور اپنے نفاق کو اپنی ہوشیاری کا نتیجہ سمجھتے ہیں حالانکہ ان کی یہ حالت اول درجے کی
حماقت کے مترادف ہوتی ہے لیکن یہ بات ان کے دماغ میں آتی ہی نہیں.ان کا مرض لاعلاج
ہو چکا ہوتا ہے.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب ان سے کہا جائے کہ آخر یہ سارے مسلمان جو ہیں
ان کے دلوں میں ایمان اور بے نفسی پائی جاتی ہے اللہ تعالی کے لئے خلوص اور ایثار پایا جاتا
ہے جس طرح اُنہوں نے اپنی تمام خواہشات اور اپنی بزرگیوں اور بڑائیوں کو اللہ تعالیٰ کی
عزت اور عظمت پر قربان کر دیا ہے تم کیوں نہیں ان کے رنگ کو اختیار کرتے اور اپنے اندر
ایمان اور بے نفسی پیدا کرتے منافق یہ سن کر جواب دیتے ہیں کہ کیا ہم ان بیوقوفوں کی طرح
ایمان لے آئیں.یہ تو احمق ہیں مالی قربانی کا مطالبہ ہوتا ہے تو یہ اپنے بیوی بچوں کو بھوکا مار
دیتے ہیں مگر قربانی ضرور دیتے ہیں.بھلا یہ بھی کوئی عقلمندی ہے کہ بیوی بچے بھوکے مرتے
رہیں اور مالی قربانیوں پر زور ہو.پھر جن منافقین کے گھر باہر ہوتے ہیں اور بظاہر ان کے
گھروں کے پہرے یا حفاظت کا کوئی انتظام نہیں ہوتا.ادھر انہیں وقت کی قربانی دینے سے
بھی گریز ہوتا ہے اور بہانہ بنا لیتے ہیں کہ ان بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ (الاحزاب (14) ہمارے یہاں تو
پہرے کا انتظام نہیں اس لئے ہم سے وقت کی قربانی کا مطالبہ نہ کریں اور ہمیں باہر نہ بھیجیں
کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ حفاظت کا سارا دارو مدار ان کی موجودگی پر ہے.حالانکہ حقیقی محافظ تو اللہ
تعالیٰ اور اس کے فرشتے ہوتے ہیں.ہمارے ملک میں بھی مختلف مواقع پر فسادات رونما
ہوتے رہے ہیں اور بہت سے احمدیوں نے اللہ تعالیٰ کی شان کو بچشم خود دیکھا ہے.بسا اوقات
ایسا ہوا ہے کہ احمدی کا اکیلا گھر تھا.ایک بھرا ہوا مجمع اس پر حملہ آور ہو مگر واپس چلا گیا اور اس
گھر کے مکین احمدیوں کو کسی قسم کی گزند نہ پہنچا سکا.اور بعض دفعہ ایسے واقعات بھی رونما ہوئے
ہیں کہ بعض احمدی گھرانوں میں مرد موجود نہیں تھے صرف عورتیں تھیں.چنانچہ جب بھی اس قسم
296
Page 305
کے گھر پر مشتعل ہجوم حملہ آور ہوا تو ان کے سامنے اکیلی عورت کھڑی ہو گئی اور خدا تعالیٰ کے
فرشتوں نے اس گھر کو اپنی حفظ وامان میں لے لیا.اس حفاظت کا ایک زبردست نظارہ حضرت
مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے اس وقت دکھایا جب آپ صرف بارہ
آدمیوں کے ساتھ دہلی تشریف لے گئے تھے جہاں ایک بڑے مشتعل ہجوم نے آپ پر حملہ کیا
اور یہ نہتے دُہری چاردیواری کے اندر اپنے قادر و توانا خدا کے سہارے بیٹھے تھے.مادی لحاظ
سے یا دنیوی سامانوں کے لحاظ سے اپنی مدافعت کا کوئی سامان ان کے پاس نہ تھا.مگر اللہ
تعالی جو عظیم قدرتوں کا مالک ہے اس کی حفاظت کا شرف انہیں حاصل تھا.چنانچہ ہجوم باہر کا
دروازہ توڑ کر اندر صحن میں داخل ہو گیا پھر اندر کے صحن کا دروازہ توڑ ہی رہے تھے کہ کسی
نامعلوم وجہ سے اپنے آپ ہی واپس چلے گئے.اب دنیا کو تو وہ وجہ نظر نہیں آتی لیکن ہمیں تو وہ
وجہ نظر آتی ہے.یہ دراصل اللہ تعالیٰ کا زبردست رُعب تھا جو اُن کے دلوں پر ڈالا گیا اور وہ اس
وجہ سے ڈر کر واپس چلے گئے.چنانچہ یہ ایک عظیم معجزہ اور اللہ تعالیٰ کے پیار کا ایک عجیب
مظاہرہ تھا جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں رونما ہوا.جس سے ہمیں بھی یہ
سبق ملتا ہے کہ اگر ہم بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ پر توکل کریں گے تو ہمیں بھی اس طرح اللہ تعالیٰ کی
حفظ وامان حاصل رہے گی اور مخالف کا کوئی وار کامیاب تو کیا ہوگا وہ اس موقعہ پر خود ہی خائب
وخاسر ہو کر لوٹ جائے گا.پس یہاں خدا تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر بار کو خدا کے سپرد کر کے خدا تعالیٰ کے
لئے اپنا وقت دینے کیلئے چلا جاتا ہے وہی عقل مند ہے اور جو شخص یہ کہتا ہے کہ میرا گھر نگا ہے
پہرے کا کوئی انتظام نہیں اجازت دیجئے کہ میں جہاد میں شامل ہونے کی بجائے گھر بار کی
حفاظت کروں.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسا شخص در اصل غیر محفوظ ہے وہ چاہے جتنے مرضی انتظام
کرے، مضبوط سے مضبوط قلعے بنالے وہ ملک الموت سے بچ نہیں سکتا وہ ایسے وقت میں اس
کے پاس پہنچ جاتا ہے کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا.297
Page 306
بعض دفعہ دشمن الہی سلسلہ پر حملہ آور ہوتا ہے اور ظاہری لحاظ سے وہ سمجھتا ہے کہ میں غالب آ
گیا ہوں.چنانچہ وہ جماعت کے امام کو کہلا بھیجتا ہے کہ آپ لوگوں کی جان صرف اس صورت
میں بچ سکتی ہے کہ آپ اس قسم کا ایک بیان جاری کر دیں.لیکن اسے یہی جواب سنا پڑتا ہے
کہ ہم خدا تعالیٰ کی حفاظت میں ہیں تم کیا تمہارے جیسے کروڑوں بھی آجائیں ہمارا کچھ بھی بگاڑ
نہیں سکتے.ہمیں اپنے قادر و توانا خدا پر بھروسہ ہے اور یقین ہے کہ اس کی حفاظت ہمارے
شامل حال ہے.اس حقیقی حفاظت اور سچی امان کو چھوڑ کر ہمارا جھوٹے وعدوں کی طرف متوجہ
ہو جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا.پس الہی سلسلوں کا یہی حال ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہی جذبہ عقلمندی کہلاتا
ہے لیکن جو منافق ہیں جن کا ذکر ان آیات میں کیا گیا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے ہوشیار ہیں
دیکھو ہم نے دنیوی حفاظت کے لئے کیسی عقلمندی، ہوشیاری اور چالاکی سے کام لیا کہ
بیک وقت دعویٰ ایمان کی وجہ سے مسلمانوں کی صفوں میں بھی شامل رہے اور پس پردہ منکرین
اسلام سے بھی بنائے رکھی.وہ اپنی اس حماقت کو عقلمندی سمجھتے ہیں حالانکہ وہ اللہ تعالی کے
غضب کا مورد ہیں.ان کے سروں پر اللہ تعالیٰ کے غضب کا کوڑا اسی طرح لہراتا ہے جس طرح
بجلی آسمان سے کوندتی ہے اور جس چیز پر گرتی ہے آنکھ جھپکنے میں اس کو بھسم کر کے رکھ دیتی...خدا تعالیٰ کے اس قہر کے کئی نشان دیہاتوں میں اکثر دیکھنے میں آتے ہیں.اللہ تعالیٰ
سب کو اپنے قہر سے بچائے.انسانی ہمدردی کے لحاظ سے احمدی یا غیر احمدی سب برابر ہیں.چنانچہ ابھی پچھلے دنوں کا یہ واقعہ ہے کہ ہماری زمینوں کے قریب ہی ایک غیر از جماعت
زمیندار کے پانچ جانور ( تین ایک طرف اور دو دوسری طرف آمنے سامنے ) باندھے ہوئے
تھے.اچانک بجلی گری اور ایک طرف کے دونوں جانوروں اور پاس کے درخت کے ایک
حصے کو ایک سیکنڈ کے اندر بالکل راکھ بنا کر رکھ دیا.اگر انسان اس درخت کو کاٹ کر اس کی
راکھ بنانا چاہتا تو شاید اس کو کئی دن لگ جاتے مگر خدا تعالیٰ کے قہر کے اس ایک جلوے نے
ایک سیکنڈ کے اندر درخت کو جلا کر راکھ کر دیا.اللہ تعالیٰ کے یہ جلوے بھی اپنے اندر کئی سبق
ہے.298
Page 307
رکھتے ہیں.اللہ تعالیٰ ان کے ذریعہ اپنے بندوں کو متنبہ کرتا ہے کہ دیکھو میرے فضل اور میری
رحمت کے بغیر ایک پل بھر کے لئے بھی تمہاری زندگی، اس کی صحت اور بقا قائم نہیں رہ سکتی.اگر میر افضل شامل حال نہ ہو تو میرے قہر کا ایک معمولی سا جلوہ تمہارے درخت وجود کو جلا کر
خاکستر کر دے.اس لئے اپنی حفاظت کے لئے میری پناہ میں آجاؤ اور میرے دامن سے اپنے
آپ کو وابستہ کر لو.پس مومن بندہ اس حقیقت سے آگاہ اور باخبر ہوتا ہے اور اسی لئے وہ ہمیشہ
اپنے رب کے حضور سجدہ ریز رہتا ہے.لیکن جب ایک منافق سے یہ کہا جائے کہ اپنے رب
سے بے نفس ایثار اور بچے خلوص کا تعلق قائم کرو اور اس کے لئے جس قربانی کا مطالبہ ہو اس کو
پورا کرو تو وہ آگے سے کہہ دیتے ہیں کہ اس قسم کا ایمان تو دراصل ایک پاگل پن کی دلیل ہے.ایک مجنونانہ فعل اور احمقانہ حرکت ہے.ہم اتنے عقلمند ہو کر بھلا کیوں اس قسم کا ایمان لائیں.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان سے کہہ دو هُمُ السُّفَهَاءُ بیوقوف اور احمق تو دراصل تم ہی ہولیکن
بیوقوف اور احمق ہونے کے علاوہ بڑے بد بخت بھی ہو کہ تمہیں اپنی بیوقوفی اور حماقت کا احساس
بھی نہیں ہوتا.وہ احمق جو اپنی حماقت کا احساس رکھتا ہے وہ خود بھی بہت سی تکلیفوں سے محفوظ
رہتا ہے اور دوسرے بھی اس کے آزار سے بہت حد تک محفوظ رہتے ہیں کیونکہ اسے یہ احساس
ہوجاتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنا دماغ نہیں دیا جتنا دوسروں کو دیا گیا ہے.لیکن جو شخص
اپنی حماقت کا احساس نہیں رکھتا وہ ہر وقت معرض خطرہ میں رہتا ہے اور نقصان سے دو چار رہتا
ہے.اسی واسطے دانشمندوں کا یہ قول ہے کہ ایک بیوقوف دوست کی نسبت ہزار عقلمند دشمن
اچھے ہوتے ہیں کیونکہ بسا اوقات ہزار عقلمند دشمن کسی کو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے جو ایک
بیوقوف دوست کے ہاتھوں اسے اُٹھانا پڑتا ہے.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان سے کہہ دو کہ میری نگاہ میں اور میری صفات سے متصف میرے
بندوں کی نگاہ میں بھی بیوقوف تم ہی ہو، خواہ تم کتنے ہی عقلمند کیوں نہ بنے پھرو.پس منافقین کی یہ بنیادی علامات ہیں جن کا ذکر ان آیات میں کیا گیا ہے.جیسا کہ میں نے
ابھی اشارہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ اپنی منافقت کو عقلمندی سمجھتے ہیں خدائے رحمن کو بھی
299
Page 308
اپنا سر دار سمجھتے ہیں اور شیطان کو بھی اپنا سردار سمجھتے ہیں اور جو خدا کا بندہ خدا کی صفت رحمانیت کا مظہر
ہے وہ بھی ظلی طور پر رحمن ہے.ہر انسان اپنے محدود دائرہ میں ظلمی طور پر اپنے اندر اللہ تعالی کی
صفات کو منعکس کر کے رب بھی ہے رحمن بھی ہے رحیم بھی ہے اور مالک بھی ہے.حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے سورۃ فاتحہ کی تفسیر میں بیان فرمایا ہے کہ ہماری
جماعت پر یہ فرض لازم ہے کہ دوست ان صفات باری تعالیٰ کو ظنی طور پر اپنے اندر بھی پیدا
کریں.پس ایک ایسا شخص جو رحمن اور شیطان میں فرق نہیں کر سکتا وہ بھلا عقلمند کیسے ہوسکتا
ہے؟ منافق بے شک اپنے آپ کو عقلمند سمجھتے پھریں اللہ تعالیٰ کا ان کے متعلق فیصلہ یہ ہے کہ
وہ پرلے درجے کے سفیہ بڑے ہی بیوقوف اور سخت احمق ہیں کیونکہ یہ تو رحمن اور شیطان میں
بھی فرق نہیں کر سکتے.یہ ان کی بیوقوفی اور حماقت کی دلیل نہیں تو اور کیا ہے اس دورنگی کو عقلمند
کون کہہ سکتا ہے کہ جب اپنے شیطان سرداروں کے پاس جاتے ہیں تو ان کی وفاداری کا دم
بھرتے ہیں لیکن مومنوں کے پاس آکر اسی زبان سے مومنانہ جذبات کا اظہار بھی کر رہے
ہوتے ہیں اور بڑی چرب زبانی سے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ
فرماتا ہے جو شخص خدائے رحمن اور شیطان ملعون میں فرق نہ کر سکے وہ سفیہ یعنی پرلے درجے کا
بیوقوف نہیں تو اور کیا ہے.لیکن اپنی سفاہت کا احساس نہ رکھنے کی وجہ سے یا محض شرارت کی
نیت سے عقلمند کے روپ میں تمہارے سامنے آئیں گے.بظاہر بڑے عقلمند بڑے مصلح
نہایت ہمدرد اور پگے مومن.لیکن در پردہ منافق ہوں گے.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے
جماعت مومنہ ! میں تم پر یہ اعتماد کر رہا ہوں اور تمہارے سامنے ان کی علامات کو کھول کھول کر
اس لئے بیان کر رہا ہوں کہ تم بھی ہمیشہ ایسے گروہ سے چوکس اور بیدار ہوجس طرح یہ لوگ مجھے
بیوقوف نہیں بنا سکے اسی طرح یہ تمہیں بھی بیوقوف نہیں بنا سکتے.(بقُدْرَتِهِ الْكَامِلَةِ )
پس اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ہر سہ جماعتوں کے متعلق ان کی خصوصیات، کیفیات اور
علامات کو ظاہر فرما دیا ہے.مومنوں کے لئے غیر محدود ترقیات کے دروازے کھولے.منکرین اسلام کے متعلق فرمایا کہ جب تک ان کی یہی کیفیت رہے گی یہ ایمان لانے کی
300
Page 309
سعادت سے محروم رہیں گے.انہیں اس وقت تک ایمان
کی توفیق نہیں مل سکتی جب تک اپنی
اس بنیادی کمزوری کو دور نہ کریں کہ اپنے ہاتھوں سے انہوں نے جو غلط قسم کی مہریں اور
پر دے اپنے دل، کان اور آنکھ پر ڈال لئے ہیں وہ ہٹا نہ دیں.جب تک ان کی یہ حالت تبدیل
نہیں ہوتی انہیں ڈرانا یانہ ڈرانا برابر ہے.اس سے ہمیں بھی یہ بتانا مقصود ہے کہ تم بھی دیکھو کہ
وہ مہریں کیسی ہیں ان کو کس طرح توڑا جا سکتا ہے تا کہ ایمان سے محروم اپنے ان بھائیوں کی
خدمت کر سکو.چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ وہ پر دے اس شکل کے ہیں، اس رنگ کے ہیں
اور ان اثرات کے حامل ہیں لہذا تم ان پردوں کو ہٹا کر اپنے بھائیوں کو جو اس وقت تک ایمان کی
دولت سے محروم ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کے نشان دیکھنے اور ان پر ایمان لانے کے قابل بنا سکتے ہو.پھر اس گروہ کا ذکر فرمایا جو مومن ہونے کا لیبل لگا کر مومن ہی کے روپ میں اُمتِ مسلمہ
میں گھسے رہتے ہیں اور اندر ہی اندر نفاق کا بیج بوتے ہوئے امت کے شیرازہ کو نقصان پہنچاتے
رہتے ہیں.ان آیات کے علاوہ بھی قرآن کریم نے کئی دوسری جگہ اس گروہ کی مختلف روحانی
بیماریوں اور اس کی مفسدانہ کارروائیوں پر بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے.لیکن یہاں ان
آیات میں اس گروہ سے متعلق چند بنیادی علامات کو واضح کیا گیا ہے.جہاں تک ان کی
بیماریوں اور ان کے فتنوں کا تعلق ہے ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ جب بیماری کہیں تو اس کا
مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا اس کی اپنی ذات کو نقصان پہنچ رہا ہے.لیکن جب فتنہ کہیں تو اس کا
مطلب یہ ہے کہ ساری جماعت کو نقصان پہنچ رہا ہے.یوں دراصل ان کی بیماریاں اور ان کے
فتنے ایک ہی تصویر کے دورخ ہیں.پس قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے منافق کی بیماریوں، اس کے فتنوں وغیرہ کے متعلق اور
پھر ان کا کس طرح ازالہ کیا جا سکتا ہے اس کے متعلق وضاحت سے بیان فرمایا ہے کہ اگر چہ
ان بیماریوں کا علاج اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے لیکن چونکہ اس کے مومن بندے اس کی صفات کے
مظہر ہوتے ہیں اس لئے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر ہونے کی حیثیت میں ان کی بیماریوں
کے علاج میں کوشاں رہتے ہیں.پس ان آیات میں منافقین کی بنیادی کمزوریوں کو بیان
301
Page 310
فرمایا.ان سے بچنے کی تلقین فرمائی اس لئے یہ مضمون اس اعتبار سے بنیادی حیثیت کا
حامل ہے کہ اس میں ان بیماریوں سے بچنے کی راہیں بتائی گئی ہیں.( خطبات ناصر جلد دوم صفحہ 850 تا865.انوار القرآن تفسیر حضرت خلیفة المسیح الثالث جلد اوّل صفحہ 107 تا121)
302
Page 311
XXXXXXXXXXXX
سورة البقرة - آيات 255 تا 258
يَا يُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَكُمْ 255.اے ایمان دارو! جو کچھ ہم نے تمہیں دیا
مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خُلَّةٌ ہے اس میں سے اس دن کے آنے سے پہلے کہ جس
میں نہ کسی قسم کی خریدو فروخت، نہ دوستی اور نہ
وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَفِرُونَ هُمُ شفاعت (کارگر) ہوگی ( خدا کی راہ میں جو کچھ ہو
سکے ) خرچ کرلو.اور (اس حکم کا انکار کرنے والے
الظَّلِمُونَ
ج
( اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہیں.اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ لَا 256.اللہ وہ ( ذات) ہے جس کے سوا پرستش کا
تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوتِ
(اور) کوئی مستحق نہیں.کامل حیات والا (اپنی
ذات میں) قائم ( اور سب کو ) قائم رکھنے والا.نہ
وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَةَ اُسے اونگھ آتی ہے اور نہ نیند ( کا وہ محتاج ہے ).جو
إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے
خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِةٍ (سب) اسی کا ہے.کون ہے جو اس کی اجازت
إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوتِ کے بغیر اس کے حضور میں سفارش کرے.جو کچھ
اُن کے سامنے ہے اور جو کچھ اُن کے پیچھے ہے وہ
( سب ہی کچھ ) جانتا ہے.اور وہ اس کی مرضی کے
سوا اس کے علم کے کسی حصہ کو ( بھی ) پانہیں سکتے.اس کا علم آسمانوں پر (بھی) اور زمین پر (بھی)
حاوی ہے.اور ان کی حفاظت اسے تھکاتی نہیں.اور
وہ بلندشان ( رکھنے) والا ( اور ) عظمت والا ہے.وَالْأَرْضِ ۚ وَلَا يَوْدُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ
الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ 257.دین کے معاملہ میں کسی قسم کا جبر ( جائز ) نہیں
الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ
(کیونکہ) ہدایت اور گمراہی کا ( باہمی ) فرق خوب
ظاہر ہو چکا ہے.پس ( سمجھ لو کہ ) جو شخص ( اپنی مرضی
303
Page 312
بِاللهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى سے) نیکی سے روکنے والے ( کی بات ماننے) سے
لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ انکار کرے اور اللہ پر ایمان رکھے تو اس نے (ایک)
نہایت مضبوط قابل اعتماد چیز کو جو (کبھی) ٹوٹنے کی
نہیں مضبوطی سے پکڑ لیا.اور اللہ بہت سنے والا ( اور )
بہت جاننے والا ہے.اللهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ 258.اللہ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لاتے
الظلمتِ إِلَى النُّوْرِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا ہیں.وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف
لاتا ہے اور جو کافر ہیں ان کے دوست نیکی سے روکنے
أو لليهمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ والے (لوگ) ہیں.وہ انہیں روشنی سے نکال کر
النُّورِ إِلَى الظُّلُمتِ أُولَيْكَ اَصْحَبُ اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں.وہ لوگ آگ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ
( میں پڑنے) والے ہیں.وہ اس میں رہیں گے.304
Page 313
الله لا إلهَ إِلَّا هُوَ الْحَى القَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا تَوْم لَهُ مَا فِي
السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ
مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا مَا
شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ
الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ (البقرة 256)
حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں:
اللہ جو جامع صفات کا ملہ اور مستحق عبادت ہے اس کا وجود بدیہی الثبوت ہے کیونکہ وہ
حتی بالذات اور قائم بالذات ہے.بجز اس کے کوئی چیز حتی بالذات اور قائم بالذات نہیں.یعنی اس کے بغیر کسی چیز میں یہ صفت پائی نہیں جاتی کہ بغیر کسی علت موجدہ کے آپ ہی موجود
اور قائم رہ سکے یا کہ اس عالم کی جو کمال حکمت اور ترتیب محکم اور موزون سے بنایا گیا ہے علت
موجبہ ہو سکے.اور یہ امر اس صانع عالم جامع صفات کاملہ کی ہستی کو ثابت کرنے والا ہے.تفصیل اس استدلال لطیف کی یہ ہے کہ یہ بات یہ ہداہت ثابت ہے کہ عالم کے اشیاء میں سے
ہر یک موجود جو نظر آتا ہے اس کا وجود اور قیام نظرًا على ذاته ضروری نہیں مثلاً زمین
کروی الشکل ہے اور قطر اس کا بعض کے گمان کے موافق تخمیناً چار ہزار کوس پختہ ہے مگر اس
بات پر کوئی دلیل قائم نہیں ہوسکتی کہ کیوں یہی شکل اور یہی مقدار اس کے لئے ضروری ہے اور
کیوں جائز نہیں کہ اس سے زیادہ یا اس سے کم ہو یا برخلاف شکل حاصل کے کسی اور شکل سے
متشکل ہو اور جب اس پر کوئی دلیل قائم نہ ہوئی تو یہ شکل اور یہ مقدار جس کے مجموعہ کا نام وجود
ہے زمین کے لئے ضروری نہ ہوا اور علی ہذا القیاس عالم کی تمام اشیاء کا وجود اور قیام غیر ضروری
ٹھہرا.اور صرف یہی بات نہیں کہ وجود ہر یک ممکن کا نظرًا على ذَاتِهِ غیر ضروری ہے بلکہ بعض
305
Page 314
صورتیں ایسی نظر آتی ہیں کہ اکثر چیزوں کے معدوم ہونے کے اسباب بھی قائم ہو جاتے ہیں
پھر وہ چیزیں معدوم نہیں ہوتیں مثلاً با وجود اس کے کہ سخت سخت قحط اور و با پڑتی ہیں مگر پھر بھی
ابتداء زمانہ سے تخم ہر یک چیز کا بچتا چلا آیا ہے حالانکہ عند العقل جائز بلکہ واجب تھا کہ ہزار ہا
شدائد اور حوادث میں سے جو ابتدا سے دنیا پر نازل ہوتی رہی کبھی کسی دفعہ ایسا بھی ہوتا کہ شدت
قحط کے وقت غلہ جو کہ خوراک انسان کی ہے بالکل مفقود ہو جاتا یا کوئی قسم غلہ کی مفقود ہو جاتی یا
کبھی شدت وبا کے وقت نوع انسان کا نام و نشان باقی نہ رہتا یا کوئی اور انواع حیوانات میں
سے مفقود ہو جاتے یا کبھی اتفاقی طور پر سورج یا چاند کی گل بگڑ جاتی یا دوسری بے شمار چیزوں سے
جو عالم کی درستی نظام کے لئے ضروری ہیں کسی چیز کے وجود میں خلل راہ پا جاتا کیونکہ کروڑ با
چیزوں کا اختلال اور فساد سے سالم رہنا اور کبھی ان پر آفت نازل نہ ہونا قیاس سے بعید ہے.پس جو چیزیں نہ ضروری الوجود ہیں، نہ ضروری القیام بلکہ ان
کا کبھی نہ کبھی بگڑ جانا ان کے باقی
رہنے سے زیادہ ترقرین قیاس ہے ان پر کبھی زوال نہ آنا اور احسن طور پر بہ ترتیب محکم اور ترکیب
ابلغ ان کا وجود اور قیام پا یا جانا اور کروڑ با ضروریات عالم میں سے کبھی کسی چیز کا مفقود نہ ہونا صریح
اس بات پر نشان ہے کہ ان سب کے لئے ایک نحیبی اور محافظ اور قیوم ہے جو جامع صفات کاملہ
یعنی مدبر اور حکیم اور رحمان اور رحیم اور اپنی ذات میں ازلی ابدی اور ہر یک نقصان سے پاک
ہے جس پر کبھی موت اور فنا طاری نہیں ہوتی بلکہ اونگھ اور نیند سے بھی جو فی الجملہ موت سے
مشابہ ہے پاک ہے.سو وہی ذات، جامع صفات کاملہ ہے جس نے اس عالم امکانی کو
برعایت کمال حکمت و موزونیت وجود عطا کیا اور ہستی کو نیستی پر ترجیح بخشی اور وہی بوجہ اپنی
کمالیت اور خالقیت اور ربوبیت اور قیومیت کے مستحق عبادت ہے.یہاں تک تو تر جمہ اس
آیت کا اللهُ لا إلهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي
الْأَرْضِ.اب بنظر انصاف دیکھنا چاہئے کہ کس بلاغت اور لطافت اور متانت اور حکمت سے اس
306
Page 315
آیت میں وجود صانع عالم پر دلیل بیان فرمائی ہے اور کس قدر تھوڑے لفظوں میں معانی کثیرہ
اور لطائف حکمیہ کو کوٹ کوٹ کر بھر دیا ہے اور ما في السَّمَوتِ وَ مَا فِي الْأَرْضِ کے لئے
ایسی محکم دلیل سے وجود ایک خالق، کامل الصفات کا ثابت کر دکھایا ہے جس کے کامل اور محیط
بیان کے برابر کسی حکیم نے آج تک کوئی تقریر بیان نہیں کی بلکہ حکماء ناقص الفہم نے ارواح
اور اجسام کو حادث بھی نہیں سمجھا اور اس راز دقیق سے بے خبر رہے کہ حیات حقیقی اور ہستی حقیقی
اور قیام حقیقی صرف خدا ہی کے لئے مسلم ہے.یہ عمیق معرفت اسی آیت سے انسان کو حاصل
ہوتی ہے جس میں خدا نے فرمایا کہ حقیقی طور پر زندگی اور بقاء زندگی صرف اللہ کے لئے حاصل
ہے جو جامع صفات کا ملہ ہے اس کے بغیر کسی دوسری چیز کو وجود حقیقی اور قیام حقیقی حاصل نہیں
اور اسی بات کو صانع عالم کی ضرورت کے لئے دلیل ٹھہرایا اور فرمایا : لَهُ مَا فِي السَّمواتِ وَمَا
في الْأَرْضِ.یعنی جبکہ عالم کے لئے نہ حیات حقیقی حاصل ہے نہ قیام حقیقی تو بالضرور اس کو ایک
علت موجبہ کی حاجت ہے جس کے ذریعہ سے اس کو حیات اور قیام حاصل ہوا.اور ضرور ہے
کہ ایسی علت موجبہ جامع صفات کا ملہ اور مدبر بالا رادہ اور حکیم اور عالم الغیب ہو.سو وہی اللہ
ہے.کیونکہ اللہ بموجب اصطلاح قرآن شریف کے اس ذات کا نام ہے جو ستجمع کمالات تامہ
ہے اسی وجہ سے قرآن شریف میں اللہ کے اسم کو جمیع صفات کا ملہ کا موصوف ٹھہرایا ہے اور جابجا
فرمایا ہے کہ اللہ وہ ہے جو کہ رب العالمین ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، مدبر بالا رادہ ہے، حکیم
ہے، عالم الغیب ہے، قادر مطلق ہے، ازلی ابدی ہے وغیرہ وغیرہ.سو یہ قرآن شریف کی ایک
اصطلاح ٹھہرائی گئی ہے کہ اللہ ایک ذات جامع جمیع صفات کاملہ کا نام ہے.اسی جہت سے
اس آیت کے سر پر بھی اللہ کا اسم لائے اور فرمایا: اللہ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ.یعنی اس
عالم بے ثبات کا قیوم، ذات جامع الکمالات ہے.یہ اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہ عالم
جس ترتیب محکم اور ترکیب ابلغ سے موجود اور مترتب ہے اس کے لئے یہ گمان کرنا باطل ہے کہ
انہیں چیزوں میں سے بعض چیزیں بعض کے لئے علت موجبہ ہوسکتی ہیں بلکہ اس حکیمانہ کام
کے لئے جو سراسر حکمت سے بھرا ہوا ہے ایک ایسے صانع کی ضرورت ہے جو اپنی ذات میں
307
Page 316
مدبر بالا رادہ اور حکیم اور علیم اور رحیم اور غیر فانی اور تمام صفات کاملہ سے متصف ہو.سو وہی اللہ
ہے جس کو اپنی ذات میں کمال تام حاصل ہے.براہین احمدیہ.روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 514-518 - حاشیہ در حاشیہ نمبر 3)
الله لا إلهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوتِ وَ
مَا فِي الْأَرْضِ یعنی خدا اپنی ذات میں سب مخلوقات کے معبود ہونے کا ہمیشہ حق رکھتا ہے
جس میں کوئی اس کا شریک نہیں.اس دلیل روشن ہے کہ وہ زندہ، ازلی ابدی ہے اور سب
چیزوں کا وہی قیوم ہے یعنی قیام اور بقا ہر چیز کا اسی کے بقا اور قیام سے ہے اور وہی ہر چیز کو
ہر دم تھامے ہوئے ہے، نہ اس پر اونگھ طاری ہوتی ہے، نہ نیند اسے پکڑتی ہے یعنی حفاظت
مخلوق سے
کبھی غافل نہیں ہوتا.پس جبکہ ہر ایک چیز کی قائمی اسی سے ہے.پس ثابت ہے کہ
ہر ایک مخلوقات آسمانوں کا اور مخلوقات زمین کا وہی خالق ہے اور وہی مالک....پرانی تحریریں.روحانی خزائن جلد 2 صفحہ 16-17)
یعنی وہی خدا ہے اس کے سوا کوئی نہیں وہی ہر ایک جان کی جان اور ہر ایک وجود کا
سہارا ہے.اس آیت کے لفظی معنے یہ ہیں کہ زندہ وہی خدا ہے اور قائم بالذات وہی خدا ہے
پس جب کہ وہی ایک زندہ ہے اور وہی ایک قائم بالذات ہے تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ ہر
ایک شخص جو اس کے سوا زندہ نظر آتا ہے وہ اسی کی زندگی سے زندہ ہے اور ہر ایک جوز مین یا
آسمان میں قائم ہے وہ اسی کی ذات سے قائم ہے.چشمه معرفت، روحانی خزائن جلد 23 صفحه 120)
حقیقی وجود اور حقیقی بقا اور تمام صفات حقیقیہ خاص خدا کے لئے ہیں کوئی اُن میں اُس کا
شریک نہیں وہی بذاتہ زندہ ہے اور باقی تمام زندے اُس کے ذریعہ سے ہیں.اور وہی اپنی
ذات سے آپ قائم ہے اور باقی تمام چیزوں کا قیام اس کے سہارے سے ہے اور جیسا کہ
موت اس پر جائز نہیں ایسا ہی ادنی درجہ کا تعطل حواس بھی جو نیند اور اونگھ سے ہے وہ بھی اُس پر
جائز نہیں مگر دوسروں پر جیسا کہ موت وارد ہوتی ہے نیند اور اونگھ بھی وارد ہوتی ہے.جو کچھ تم
زمین میں دیکھتے ہو یا آسمان میں وہ سب اُسی کا ہے اور اُسی سے ظہور پذیر اور قیام پذیر ہے.308
Page 317
کون ہے جو بغیر اس کے حکم کے اُس کے آگے شفاعت کرسکتا ہے؟ وہ جانتا ہے جولوگوں
کے آگے ہے اور جو پیچھے ہے.یعنی اس کا علم حاضر اور غائب پر محیط ہے اور کوئی اس کے علم کا
کچھ بھی احاطہ نہیں کر سکتا لیکن جس قدر وہ چاہیے.اُس کی قدرت اور علم کا تمام زمین و آسمان پر
تسلط ہے.وہ سب کو اٹھائے ہوئے ہے، یہ نہیں کہ کسی چیز نے اُس کو اٹھا رکھا ہے اور وہ
آسمان وزمین اور اُن کی تمام چیزوں کے اٹھانے سے تھکتا نہیں اور وہ اس بات سے بزرگ تر
ہے کہ ضعف و ناتوانی اور کم قدرتی اُس کی طرف منسوب کی جائے.( چشمه معرفت، روحانی خزائن جلد 23 صفحہ 273 274)
تمام مخلوقات، اجرام فلکی سے لے کر ارضی تک اپنی بناوٹ ہی میں عبودیت کا رنگ
رکھتی ہے.ہر پتے سے یہ پتہ ملتا ہے ہر شاخ اور آواز سے یہ صدا نکلتی ہے کہ اُلوہیت اپنا
کام کر رہی ہے.اس کے عمیق در عمیق تصرفات جن کو ہم خیال اور قوت سے بیان نہیں کر
سکتے بلکہ کامل طور پر سمجھ بھی نہیں سکتے اپنا کام کر رہے ہیں.چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ
اللهُ لا إلهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ یعنی اللہ تعالی ہی ایک ایسی ذات ہے جو جامع صفاتِ
کاملہ اور ہر ایک نقص سے منزہ ہے وہی مستحق عبادت ہے.اُسی کا وجود بدیہی الثبوت
ہے.کیونکہ وہ جی بالذات اور قائم بالذات ہے.اور بجز اس کے اور کسی چیز میں حتی بالذات
اور قائم بالذات ہونے کی صفت نہیں پائی جاتی.کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کے بدوں اور کسی
میں یہ صفت نظر نہیں آتی کہ بغیر کسی علت موجبہ کے آپ ہی موجود اور قائم ہو.یا کہ اُس
عالم کی، جو کمال حکمت اور ترتیب محکم و موزون سے بنایا گیا ہے، علت موجبہ ہو سکے.غرض اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے سوا اور کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو ان مخلوقات
عالم میں تغیر و تبدل کر سکتا ہو یا ہر ایک شے کی حیات کا موجب اور قیام کا باعث ہو.اس
آیت پر نظر کرنے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وجودی مذہب حق سے دور چلا گیا ہے اور
اُس نے صفات الہیہ کے سمجھنے میں ٹھو کر کھائی ہے.وہ معلوم نہیں کرسکتا کہ اُس نے
عبودیت اور الوہیت کے ہی رشتہ پر ٹھو کر کھاتی ہے.اصل یہ معلوم ہوتی ہے کہ اُن میں
309
Page 318
سے جولوگ اہل کشف ہوئے ہیں اور اُن میں سے اہل مجاہدہ نے دریافت کرنا چاہا تو
عبودیت اور ربوبیت کے رشتہ میں امتیاز نہ کر سکے اور خلق الاشیاء کے قائل ہو گئے.ر پورٹ جلسہ سالانہ 1897، صفحہ 138 ، 139)
یعنی خدا ہی ہے جو قابل پرستش ہے کیونکہ وہی زندہ کرنے والا ہے اور اسی کے سہارے
سے انسان زندہ رہ سکتا ہے.یعنی انسان کا ظہور ایک خالق کو چاہتا تھا اور ایک قیوم کو، تا خالق اس
کو پیدا کرے اور قیوم اس کو بگڑنے سے محفوظ رکھے.سو وہ خدا خالق بھی ہے اور قیوم بھی.اور جب
انسان پیدا ہو گیا تو خالقیت کا کام تو پورا ہو گیا مگر قیومیت کا کام ہمیشہ کے لئے ہے، اسی لئے دائمی
استغفار کی ضرورت پیش آئی.غرض خدا کی ہر ایک صفت کے لئے ایک فیض ہے.پس استغفار
صفت قیومیت کا فیض حاصل کرنے کے لئے کرتے رہنے کی طرف اشارہ سورۃ فاتحہ کی اس آیت
میں ہے إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی اس بات کی
مدد چاہتے ہیں کہ تیری قیومیت اور ربوبیت ہمیں مدد دے اور ہمیں ٹھوکر سے بچاوے تا ایسا نہ ہو کہ
کمزوری ظہور میں آوے اور ہم عبادت نہ کرسکیں.( عصمت انبیاء علیہم السلام، روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 672)
هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ یعنی حقیقی حیات اسی کو ہے اور دوسری سب چیزیں اس سے پیدا اور
اس کے ساتھ زندہ ہیں یعنی در حقیقت سب جانوں کی جان اور سب طاقتوں کی طاقت وہی ہے
لیکن اگر یہ خیال کیا جائے کہ وہ قدیم سے الگ کا الگ چلا آتا ہے اور اس کی ربوبیت کا کسی
چیز پر احاطہ نہیں اور کوئی چیز اس سے ظہور پذیر نہیں ہوئی تو اس صورت میں علم کائنات تو اسے
کیا ہوگا بلکہ محدود چیزوں میں سے وہ بھی ایک چیز ہوگی جس کا کوئی اور محدد تلاش کرنا پڑے گا.سرمه چشم آریہ ، روحانی خزائن جلد 2 صفحہ 224 ،225 حاشیہ )
حمد خدا تعالیٰ کے دو نام ہیں؛ ایک حتی دوسرا قیوم حتی کے یہ معنے ہیں کہ خود بخود زندہ
اور دوسری چیزوں کو زندگی بخشنے والا اور قیوم کے یہ معنے ہیں کہ اپنی ذات میں آپ قائم اور
اپنی پیدا کردہ چیزوں کو اپنے سہارے سے باقی رکھنے والا.پس خدا تعالیٰ کے نام قیوم سے وہ
310
Page 319
چیز فائدہ اٹھا سکتی ہے جو پہلے اس سے اس کے نام حی سے فائدہ اٹھا چکی ہو.کیونکہ خدا تعالی
اپنی پیدا کردہ چیزوں کو سہارا دیتا ہے، نہ ایسی چیزوں کو جن کے وجود اور ہستی کو اس کا ہاتھ ہی
نہیں چھوا.پس جو شخص خدا تعالیٰ کو حتی یعنی پیدا کرنے والا مانتا ہے اسی کا حق ہے کہ اس کو
قیوم بھی مانے.یعنی اپنی پیدا کردہ کو اپنی ذات سے سہارا دینے والا.لیکن جو شخص خدا تعالیٰ
کو حتی یعنی پیدا کرنے والا نہیں جانتا اس کا حق نہیں ہے کہ اس کی نسبت یہ اعتقاد رکھے کہ وہ
ان چیزوں کو ، ان کے رہنے میں سہارا دینے والا ہے.کیونکہ سہارا دینے کے یہ معنے ہیں کہ اگر
اس کا سہارا نہ ہو وہ چیزیں معدوم ہو جائیں.اور ظاہر ہے کہ جن چیزوں کا اس کی طرف سے
وجود نہیں وہ چیزیں اپنے بقائے وجود میں اس کی محتاج بھی نہیں ہوسکتیں اور اگر وہ بقائے وجود
میں محتاج ہیں تو اس وجود کی پیدائش میں بھی محتاج ہیں.غرض خدا تعالیٰ کے یہ دونوں اسم حتی و قیوم اپنی تاثیر میں ایک دوسرے سے تعلق رکھتے
ہیں کبھی علیحدہ علیحدہ نہیں ہو سکتے.پس جن لوگوں کا یہ مذہب ہے کہ خدا روحوں اور ذرات
کا پیدا کرنے والا نہیں وہ اگر عقل اور سمجھ سے کچھ کام لیں تو اُن کو اقرار کرنا پڑے گا کہ خدا تعالیٰ
ان چیزوں کا قیوم بھی نہیں.یعنی وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ خدا تعالیٰ کے سہارے سے ذرّات یا
ارواح پیدا ہوئے ہیں بلکہ خدا تعالیٰ کے سہارے کی محتاج وہ چیزیں ہیں جو اس کی پیدا کردہ
ہیں.غیر کو جو اپنے وجود میں اس کا محتاج نہیں اس کے سہارے کی کیوں حاجت پڑ گئی ؟ یہ دعویٰ
بے دلیل ہے.(چشمه مسیحی، روحانی خزائن جلد 20 صفحه 362 ، 363)
جاننا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن شریف نے دو نام پیش کئے ہیں؛ آتی اور
الْقَيُّوم - اتختی کے معنے ہیں خود زندہ اور دوسرں کو زندگی عطا کرنے والا، القیوم خود قائم اور
وں کے قیام کا اصلی باعث.ہر ایک چیز کا ظاہری، باطنی قیام اور زندگی، انہیں دونوں
صفات کے طفیل سے ہے.پس حتی کا لفظ چاہتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے جیسا کہ اس کا
مظہر سورۃ فاتحہ میں اِيَّاكَ نَعْبُدُ ہے اور الْقَيُّوم چاہتا ہے کہ اس سے سہارا طلب کیا جاوے
311
Page 320
اس کو ايَّاكَ نَسْتَعِينُ کے لفظ سے ادا کیا گیا ہے
حی کا لفظ عبادت کو اس لئے چاہتا ہے کہ اس نے پیدا کیا اور پھر پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا
جیسے مثلاً معمار جس نے عمارت کو بنایا ہے اس کے مر جانے سے عمارت کا کوئی حرج نہیں
ہے مگر انسان کو خدا کی ضرورت ہر حال میں لاحق رہتی ہے اس لئے ضروری ہوا کہ خدا سے
طاقت طلب کرتے رہیں اور یہی استغفار ہے.مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ
ا خدا کے اڈن کے سوا کوئی شفاعت نہیں ہو سکتی.قرآن شریف کی رُو سے شفاعت کے
معنے یہ ہیں کہ ایک شخص اپنے بھائی کے لئے دُعا کرے کہ وہ مطلب اس کو حاصل ہو جائے یا کوئی
بلاٹل جائے.پس قرآن شریف کا حکم ہے کہ جو شخص خدائے تعالیٰ کے حضور میں زیادہ جھکا ہوا
ہے وہ اپنے کمزور بھائی کے لئے دُعا کرے کہ اس کو وہ مرتبہ حاصل ہو یہی حقیقتِ شفاعت
ہے.سو ہم اپنے بھائیوں کے لئے بیشک دُعا کرتے ہیں کہ خدا ان کو قوت دے اور ان کی بلا
ڈور کرے اور یہ ایک ہمدردی کی قسم ہے.پس اگر وید نے اس ہمدردی کو نہیں سکھلایا اور وید کی
رُو سے ایک بھائی دوسرے کے لئے دُعا نہیں کر سکتا تو یہ بات وید کے لئے قابل تعریف
نہیں بلکہ ایک سخت عیب ہے.چونکہ تمام انسان ایک جسم کی طرح ہیں اس لئے خدا نے ہمیں
بار بارسکھلایا ہے کہ اگر چہ شفاعت کو قبول کرنا اس کا کام ہے مگر تم اپنے بھائیوں کی شفاعت
میں یعنی ان کے لئے دُعا کرنے میں لگے رہو اور شفاعت سے یعنی ہمدردی کی دُعا سے باز نہ رہو
کہ تمہارا ایک دوسرے پر حق ہے.اصل میں شفاعت کا لفظ شفع سے لیا گیا ہے.شفع : بجفت
کو کہتے ہیں جو طاق کی ضد ہے.پس انسان کو اس وقت شفیع کہا جاتا ہے جبکہ وہ کمال ہمدردی
دوسرے کا جفت ہو کر اس میں فنا ہو جاتا ہے اور دوسرے کے لئے ایسی ہی عافیت مانگتا
ہے جیسا کہ اپنے نفس کے لئے.اور یادر ہے کہ کسی شخص کا دین کامل نہیں ہوسکتا جب تک کہ
شفاعت کے رنگ میں ہمدردی اس میں پیدا نہ ہو بلکہ دین کے دو ہی کامل حصے ہیں؛ ایک خدا
312
Page 321
سے محبت کرنا اور ایک بنی نوع سے اس قدر محبت کرنا کہ ان کی مصیبت کو اپنی مصیبت سمجھ لینا اور
ان کے لئے دُعا کرنا جس کو دوسرے لفظوں میں شفاعت کہتے ہیں.(نسیم دعوت، روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 463 464)
یعنی کس کی مجال ہے کہ بغیر اذنِ الہی کے کسی کی شفاعت کر سکے؟
خدا کا قدیم سے قانونِ قدرت ہے کہ وہ تو بہ اور استغفار سے گناہ معاف کرتا ہے.اور نیک
لوگوں کی شفاعت کے طور پر دُعا بھی قبول کرتا ہے.شفیع کا لفظ شفع سے نکلا ہے جس کے معنے بجفت کے ہیں.اس لئے شفیع وہ ہوسکتا ہے جو
دو مقامات کا مظہر اتم ہو.یعنی مظہر کامل لاہوت اور ناسوت کا ہو.لاہوتی مقام کا مظہر کامل
ہونے سے یہ مراد ہے کہ اس کا خدا کی طرف صعود ہو، وہ خدا سے حاصل کرے اور ناسوتی مقام
کے مظہر کا یہ مفہوم ہے کہ مخلوق کی طرف اس کا نزول ہو جو خدا سے حاصل کرے.وہ مخلوق کو
پہنچا دے.اور مظہر کامل ان مقامات کا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اسی کی طرف
اشارہ ہے : دَنَا فَتَدَلی فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ ادنى.(النجم 10-9)
ہم دعویٰ سے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑوں کامل حصہ مقامِ لاہوت کا کسی
نبی میں نہیں آیا.اور ناسوتی حصہ چاہتا ہے بشری لوازم کو ساتھ رکھے اور حضور علیہ الصلوۃ
والسلام میں یہ ساری باتیں پوری پائی جاتی ہیں.آپ نے شادیاں بھی کیں، بچے بھی ہوئے ،
دوستوں کا زمرہ بھی تھا ، فتوحات کر کے اختیاری قوتوں کے ہوتے ہوئے انتقام چھوڑ کر رحم کر
کے بھی دکھایا.جب تک انسان کے پیرا یہ پورے نہ ہوں وہ پوری ہمدردی نہیں کرسکتا، اُس
حصہ اخلاق فاضلہ میں وہ نامکمل رہے گا مثلاً جس نے شادی ہی نہیں کی وہ بیوی اور بچوں کے
حقوق کی کیا قدر کر سکتا ہے؟ اور ان پر اپنی شفقت اور ہمدردی کا کیا نمونہ دکھا سکتا ہے؟
رہبانیت ہمدردی کو دور کر دیتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ اسلام نے رہبانیت کو نہیں رکھا.غرض کامل شفیع و ہی ہو سکتا ہے جس میں یہ دونوں حصے کامل طور پر پائے جائیں.چونکہ یہ
ایک ضروری امر تھا کہ شفیع ان دونوں مقامات کا مظہر ہو.اللہ تعالیٰ نے ابتدائے آفرینش سے
313
Page 322
ہی اس سلسلہ کا ظل قائم رکھا.یعنی آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو لا ہوتی حصہ تو اس میں یوں
رکھ دیا جب کہا فإذَا سَوَّيْتُهُ وَ نَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَجِدِينَ ( الحجر 30) اور
ناسوتی حصہ یوں رکھا کہ حوا کو اس سے پیدا کیا.یعنی جب روح پھونکی تو ایک جوڑ آدم کا خدا
تعالیٰ سے قائم ہوا اور جب خوان کالی تو دوسرا جوڑ مخلوق کے ساتھ ہونے کی وجہ سے ناسوتی ہو گیا.پس جب تک یہ دونوں حصے کامل طور پر کامل انسان میں نہ پائے جاویں وہ شفیع نہیں ہوسکتا.جیسے آدم کی پسلی سے تو انکلی اسی طرح پر کامل انسان کی پسلی سے مخلوق نکلتی ہے.الحکم جلد 6 نمبر 8 مورخہ 28 فروری 1902 ءصفحہ 6،5)
حقیقی اور سچی بات یہ ہے جو میں نے پہلے بھی بیان کی تھی کہ شفیع کے لئے ضروری ہے کہ
اول خدا تعالیٰ سے تعلق کامل ہوتا کہ وہ خدا سے فیض کو حاصل کرے اور پھر مخلوق سے شدید
تعلق ہوتا کہ وہ فیض اور خیر جو وہ خدا سے حاصل کرتا ہے مخلوق کو پہنچا وے جب تک یہ دونوں تعلق
شدید نہ ہوں شفیع نہیں ہو سکتا.پھر اسی مسئلہ پر تیسری بحث قابل غور یہ ہے کہ جب تک نمونے نہ
دیکھے جائیں کوئی مفید نتیجہ نہیں نکل سکتا اور ساری بحثیں فرضی ہیں.مسیح کے نمونہ کو دیکھ لو کہ چند
حواریوں کو بھی درست نہ کر سکے، ہمیشہ ان کوست اعتقاد کہتے رہے بلکہ بعض کو شیطان بھی کہا
اور انجیل کی رو سے کوئی نمونہ کامل ہونا ثابت نہیں ہوتا.بالمقابل ہمارے نبی کریم صلی اللہ
علیہ وسلم کامل نمونہ ہیں کہ کیسے روحانی اور جسمانی طور پر انہوں نے عذاب الیم سے چھوڑ ایا اور
گناہ کی زندگی سے ان کو نکالا کہ عالم ہی پلٹ دیا، ایسا ہی حضرت موسیٰ کی شفاعت سے بھی فائدہ
پہنچا.عیسائی جو مسیح کو مثیل موسی قرار دیتے ہیں تو یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ موسیٰ کی طرح انہوں
نے گناہ سے قوم کو بچایا ہو بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح کے بعد قوم کی حالت بہت ہی بگڑ گئی.اور
اب بھی اگر کسی کو شک ہو تو لنڈن یا یورپ کے دوسرے شہروں میں جا کر دیکھ لے کہ آیا گناہ
سے چھڑا دیا ہے یا پھنسا دیا ہے؟ اور یوں کہنے کو تو ایک چوہڑا بھی کہہ سکتا ہے کہ بالمیک نے
چھوڑ ایا مگر یہ نرے دعوے ہی دعوے ہیں جن کے ساتھ کوئی واضح ثبوت نہیں ہے.پس
عیسائیوں
کا یہ کہنا کہ مسیح چھوڑانے کے لئے آیا تھا ایک خیالی بات ہے.جبکہ ہم دیکھتے ہیں
314
Page 323
کہ ان کے بعد قوم کی حالت بہت بگڑ گئی اور روحانیت سے بالکل دُور جا پڑی.ہاں! سچا شفیع اور کامل شفیع آ نحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم میں جنہوں نے قوم کو بت پرستی اور ہر قسم کے
فسق و فجور کی گندگیوں اور ناپاکیوں سے نکال کر اعلی درجہ کی قوم بنا دیا اور پھر اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہر
زمانہ میں آپ کی پاکیزگی اور صداقت کے ثبوت کے لئے اللہ تعالی نمونہ بھیج دیتا ہے.الحکم جلد 6 نمبر 10 مورخہ 17 مارچ1902ءصفحہ5،4)
مامور من اللہ کی دُعاؤں کا گل جہان پر اثر ہوتا ہے اور یہ خدا تعالیٰ کا ایک بار یک
قانون ہے جس کو ہر ایک شخص نہیں سمجھ سکتا.جن لوگوں نے شفیع کے مسئلہ سے انکار کیا ہے
انہوں نے سخت غلطی کھائی ہے.شفیع کو قانونِ قدرت چاہتا ہے.اس کو ایک تعلق شدید
خدا تعالیٰ سے ہوتا ہے اور دوسر امخلوق سے مخلوق کی ہمدردی اس میں اس قدر ہوتی ہے کہ یوں
کہنا چاہئے کہ اس کے قلب کی بناوٹ ہی ایسی ہوتی ہے کہ وہ ہمدردی کے لئے جلد متاثر ہو جاتا
ہے.اس لئے وہ خدا سے لیتا ہے اور اپنی عقد ہمت اور توجہ سے مخلوق کو پہنچاتا ہے اور اپنا اثر
اس پر ڈالتا ہے اور یہی شفاعت ہے.انسان کی دُعا اور توجہ کے ساتھ مصیبت کا رفع ہونا یا معصیت اور ذنوب کا کم ہونا یہ سب
شفاعت کے نیچے ہے.تو جہ سب پر اثر کرتی ہے خواہ مامور کو اپنے ساتھ تعلق رکھنے والوں کا
نام اور ( پتہ ) بھی یاد ہو نہ ہو.الحکم جلد 6 نمبر 11 مورخہ 24 / مارچ 1902 ، صفحہ 6)
یہ ہرگز نہ سمجھنا چاہئے کہ شفاعت کوئی چیز نہیں.ہمارا ایمان ہے کہ شفاعت حق ہے
اور اس پر یہ نص صریح ہے : صَلِّ عَلَيْهِمْ اِنَّ صَلوتَكَ سَكَن لَّهُمْ (التوبة 103) سَكَن
لَّهُمْ یہ شفاعت کا فلسفہ ہے یعنی جو گناہوں میں نفسانیت کا جوش ہے وہ ٹھنڈا پڑ جاوے
شفاعت کا نتیجہ یہ بتایا ہے کہ گناہ کی زندگی پر ایک موت وارد ہو جاتی ہے اور نفسانی جوشوں اور
جذبات میں ایک برودت آجاتی ہے.جس سے گناہوں کا صدور بند ہو کر ان کے بالمقابل
نیکیاں شروع ہو جاتی ہیں پس شفاعت کے مسئلہ نے اعمال کو بیکار نہیں کیا بلکہ اعمال حسنہ کی
315
Page 324
تحریک کی ہے.شفاعت کے مسئلہ کے فلسفہ کو نہ سمجھ کر احمقوں نے اعتراض کیا ہے اور
شفاعت اور کفارہ کو ایک قرار دیا حالانکہ یہ ایک نہیں ہو سکتے ہیں کفارہ اعمال حسنہ سے مستغنی
کرتا ہے اور شفاعت اعمال حسنہ کی تحریک.جو چیز اپنے اندر فلفہ نہیں رکھتی ہے وہ بیچ ہے.ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ اسلامی اصول اور عقائد اور اس کی ہر تعلیم اپنے اندر ایک فلسفہ رکھتی ہے اور
علمی پیرایہ اس کے ساتھ موجود ہے جو دوسرے مذاہب کے عقائد میں نہیں ملتا.شفاعت اعمال حسنہ کی محرک کس طرح پر ہے؟ اس سوال کا جواب بھی قرآن شریف ہی
سے ملتا ہے اور ثابت ہوتا ہے کہ وہ کفارہ کا رنگ اپنے اندر نہیں رکھتی جو عیسائی مانتے ہیں
کیونکہ اس پر حصر نہیں کیا جس سے کا ہلی اور سُستی پیدا ہوتی بلکہ فرمایا: إِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَلَى
فَإِنِّي قَرِيب (البقرة 187) یعنی جب میرے بندے میرے بارے میں تجھ سے سوال کریں کہ
وہ کہاں ہے؟ تو کہہ دے کہ میں قریب ہوں.قریب والا تو سب کچھ کرسکتا ہے، ڈور والا کیا
کرے گا؟ اگر آگ لگی ہوئی ہو تو دور والے کو جب تک خبر پہنچے اُس وقت تک تو شائد وہ جل
کر خاک سیاہ بھی ہو چکے.اس لئے فرمایا کہ کہہ دو میں قریب ہوں.پس یہ آیت بھی قبولیتِ دعا کا ایک راز بتاتی ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور
طاقت پر ایمان کامل پیدا ہو اور اُسے ہر وقت اپنے قریب یقین کیا جاوے اور ایمان ہو کہ وہ ہر
پکار کو سنتا ہے.بہت سی دُعاؤں کے رڈ ہونے کا یہ بھی سر ہے کہ دُعا کرنے والا اپنی ضعیف
الایمانی سے دُعا کو مسترد کرالیتا ہے اس لئے یہ ضروری ہے کہ دُعا کو قبول ہونے کے لائق بنایا
جاوے کیونکہ اگر وہ دُعا خدا تعالیٰ کی شرائط کے نیچے نہیں ہے تو پھر اس کو خواہ سارے نبی بھی مل کر
کریں تو قبول نہ ہوگی اور کوئی فائدہ اور نتیجہ اس پر مترتب نہیں ہو سکے گا.اب یہ بات سوچنے کے قابل ہے کہ ایک طرف تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا: صل
عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلونَكَ سَكَن لَّهُمْ (التوبة 103) تيرى صلوۃ سے ان کو ٹھنڈ پڑ جاتی ہے اور
جوش و جذبات کی آگ سرد ہو جاتی ہے دوسری طرف فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي (البقرة187) كا
بھی حکم فرمایا.ان دونوں آیتوں کے ملانے سے دُعا کرنے اور کرانے والے کے تعلقات،
316
Page 325
پھر ان تعلقات سے جو نتائج پیدا ہوتے ہیں اُن
کا بھی پتہ لگتا ہے کیونکہ صرف اسی بات پر منحصر
نہیں کر دیا کہ آنحضرت کی شفاعت اور دُعا ہی کافی ہے اور خود کچھ نہ کیا جاوے.اور نہ یہی
فلاح کا باعث ہو سکتا ہے کہ آنحضرت کی شفاعت اور دعا کی ضرورت ہی نہ سمجھی جاوے.الحکم جلد 7 نمبر 9 مورخہ 10 / مارچ1903 ، صفحہ 3،2)
ما دعا اسی کو فائدہ پہنچا سکتی ہے جو خود بھی اپنی اصلاح کرتا ہے اور خدا تعالیٰ کے ساتھ
اپنے سچے تعلق کو قائم کرتا ہے.پیغمبر کسی کے لئے اگر شفاعت کرے لیکن وہ شخص جس کی
شفاعت کی گئی ہے اپنی اصلاح نہ کرے اور غفلت کی زندگی سے نہ نکلے تو وہ شفاعت اس کو
فائدہ نہیں پہنچا سکتی.احکم جلد 7 نمبر 11 مورخہ 24 مارچ 1903، صفحہ 7)
مذہبی مسائل میں سے نجات اور شفاعت کا مسئلہ ایک ایسا عظیم الشان اور مدارالمہام
مسئلہ ہے کہ مذہبی پابندی کے تمام اغراض اسی پر جا کر ختم ہو جاتے ہیں.اور کسی مذہب کے
صدق اور سچائی کے پرکھنے کے لئے وہی ایک ایسا صاف اور کھلا کھلا نشان ہے جس کے ذریعہ
سے پوری تسلی اور اطمینان سے معلوم ہو سکتا ہے کہ فلاں مذہب درحقیقت سچا اور خدا کی
طرف سے ہے اور یہ بات بالکل راست اور درست ہے کہ جس مذہب نے اس مسئلہ کو صحیح
طور پر بیان نہیں کیا یا اپنے فرقہ میں نجات یافتہ لوگوں کے موجودہ نمونے کھلے کھلے امتیاز کے
ساتھ دکھلا نہیں سکا اس مذہب کے باطل ہونے کے لئے کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں.مگر
جس مذہب نے کمال صحت سے نجات کی اصل حقیقت دکھلائی ہے اور نہ صرف اس قدر بلکہ
اپنے موجودہ زمانے میں ایسے انسان بھی پیش کئے ہیں جن میں کامل طور پر نجات کی روح پھونکی
گئی ہے اس نے مہر لگا دی ہے کہ وہ سچا اور منجانب اللہ ہے.یہ تو ظاہر ہے کہ ہر ایک انسان طبعا اپنے دل میں محسوس کرتا ہے کہ وہ صد با طرح کی
غفلتوں اور پردوں اور نفسانی حملوں اور لغزشوں اور کمزوریوں اور جہالتوں اور قدم قدم پر
تاریکیوں اور ٹھوکروں اور مسلسل خطرات اور وساوس کی وجہ سے اور نیز دنیا کی انواع اقسام کی
317
Page 326
آفتوں اور بلاؤں کے سبب سے ایک ایسے زبر دست ہاتھ کا ضرور محتاج ہے جو اُس کو اِن تمام
مکروہات سے بچاوے.کیونکہ انسان اپنی فطرت میں ضعیف ہے اور وہ کبھی ایک دم کے لئے
بھی اپنے نفس پر بھروسہ نہیں کر سکتا کہ وہ خود بخود نفسانی ظلمات سے باہر آ سکتا ہے.یہ تو انسانی
کانشنس کی شہادت ہے اور ماسوا اس کے اگر غور اور فکر سے کام لیا جائے تو عقل سلیم بھی اسی کو
چاہتی ہے کہ نجات کے لئے شفیع کی ضرورت ہے کیونکہ خدا تعالیٰ نہایت درجہ تقدس اور تطہر
کے مرتبہ پر ہے اور انسان نہایت درجہ ظلمت اور معصیت اور آلودگی کے گڑھے میں ہے اور
بوجه فقدان مناسبت اور مشابہت عام طبقہ انسانی گروہ کا اس لائق نہیں کہ وہ براہ راست
خدا تعالیٰ سے فیض پا کر مرتبہ نجات کا حاصل کرلیں.پس اس لئے حکمت اور رحمت الہی نے یہ
تقاضا فرمایا کہ نوع انسان اور اس میں بعض افراد کا ملہ جو اپنی فطرت میں ایک خاص فضیلت
رکھتے ہوں درمیانی واسطہ ہوں اور وہ اس قسم کے انسان ہوں جن کی فطرت نے کچھ حصہ
صفات لاہوتی سے لیا ہو اور کچھ حصہ صفات ناسوتی سے تا بباعث لاہوتی مناسبت کے خدا سے
فیض حاصل کریں.اور بباعث ناسوتی مناسبت کے اس فیض کو جو اوپر سے لیا ہے نیچے کو یعنی
بنی نوع کو پہنچاویں اور یہ کہنا واقعی صحیح ہے کہ اس قسم کے انسان بوجہ زیادت کمال لا ہوتی اور
ناسوتی کے دوسرے انسانوں سے ایک خاص امتیاز رکھتے ہیں گویا یہ ایک مخلوق ہی الگ ہے
کیونکہ جس قدر ان لوگوں کو خدا کے جلال اور عظمت ظاہر کرنے کے لئے جوش دیا جاتا ہے اور
جس قدر ان کے دلوں میں وفاداری کا مادہ بھرا جاتا ہے اور پھر جس قدر بنی نوع کی ہمدردی کا
جوش ان کو عطا کیا جاتا ہے، وہ ایک ایسا امر فوق العادت ہے جو دوسرے کے لئے اس کا تصور
کرنا بھی مشکل ہے.ہاں! یہ بھی یادرکھنے کے لائق ہے کہ یہ تمام اشخاص ایک مرتبہ پر نہیں
ہوتے بلکہ ان فطرتی فضائل میں کوئی اعلیٰ درجہ پر ہے کوئی اس سے کم اور کوئی اس سے کم.اور ایک سلیم العقل کا پاک کانشنس سمجھ سکتا ہے کہ شفاعت کا مسئلہ کوئی بناوٹی اور مصنوعی
مسئلہ نہیں ہے بلکہ خدا کے مقرر کردہ انتظام میں ابتدا سے اس کی نظیر میں موجود ہیں اور قانونِ
قدرت میں اس کی شہادتیں صریح طور پر ملتی ہیں.318
Page 327
اب شفاعت کی فلاسفی یوں سمجھنی چاہئے کہ شفع لغت میں جفت کو کہتے ہیں پس شفاعت
کے لفظ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ ضروری امر جو شفیع کی صفات میں سے ہوتا ہے یہ
ہے کہ اس کو دوطرفہ اتحاد حاصل ہو یعنی ایک طرف اس کے نفس کو خدا تعالیٰ سے تعلق شدید ہو
ایسا کہ گویا وہ کمال اتحاد کے سبب حضرت احدیت کے لئے بطور جفت اور پیوند کے ہو اور
دوسری طرف اس کو مخلوق سے بھی شدید تعلق ہو گویا وہ ان کے اعضا کی ایک جز ہو.پس
شفاعت کا اثر مترتب ہونے کے لئے در حقیقت یہی دو جز ہیں جن پر ترتیب اثر موقوف ہے.یہی راز ہے جو حکمتِ الہیہ نے آدم کو ایسے طور سے بنایا کہ فطرت کی ابتدا سے ہی اس کی
سرشت میں دو قسم کے تعلق قائم کر دئیے یعنی ایک تعلق تو خدا سے قائم کیا جیسا قرآن شریف
میں فرمایا: فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَجِدِينَ (الحجر (30) یعنی جب میں
آدم کو ٹھیک ٹھیک بنالوں اور اپنی روح اس میں پھونک دوں تو اے فرشتو! اسی وقت تم سجدہ میں
گر جاؤ.اس مذکورہ بالا آیت سے صاف ثابت ہے کہ خدا نے آدم میں اس کی پیدائش کے
ساتھ ہی اپنی روح پھونک کر اس کی فطرت کو اپنے ساتھ ایک تعلق قائم کر دیا.سو یہ اس لئے
کیا گیا کہ تا انسان کو فطرتاً خدا سے تعلق پیدا ہو جائے.ایسا ہی دوسری طرف یہ بھی ضروری تھا
کہ ان لوگوں سے بھی فطرتی تعلق ہو جو بنی نوع کہلائیں گے کیونکہ جبکہ ان کا وجود، آدم کی بڑی
میں سے ہڈی اور گوشت میں سے گوشت ہوگا تو وہ ضرور اس روح میں سے بھی حصہ لیں گے جو آدم
میں پھونکی گئی پس اس لئے آدم طبعی طور پر ان کا شفیع ٹھہرے گا.کیونکہ باعث نفخ روح جو
راستبازی آدم کی فطرت کو دی گئی ہے ضرور ہے کہ اس کی راست بازی کا کچھ حصہ اس شخص
کو بھی ملے جو اس میں سے نکلا ہے جیسا کہ ظاہر ہے کہ ہر ایک جانور کا بچہ اس کی صفات اور
افعال میں سے حصہ لیتا ہے اور دراصل شفاعت کی حقیقت بھی یہی ہے کہ فطرتی وارث اپنے
مورث سے حصہ لے کیونکہ ابھی ہم بیان کر چکے ہیں کہ شفاعت کا لفظ شفع کے لفظ سے نکلا ہے
جوز وج کو کہتے ہیں.پس جو شخص فطرتی طور پر ایک دوسرے شخص کا روج ٹھہر جائے گا ضرور
319
Page 328
اس کی صفات میں سے حصہ لے گا.اسی اصول پر تمام سلسلہ خلقی توارث کا جاری ہے یعنی انسان
کا بچہ انسانی قویٰ میں سے حصہ لیتا ہے اور گھوڑے کا بچہ گھوڑے کے قومی میں سے حصہ لیتا
ہے اور بکری کا بچہ بکری کے قومی میں سے حصہ لیتا ہے اور اسی وراثت کا نام دوسرے لفظوں
میں شفاعت سے فیضیاب ہونا ہے کیونکہ جبکہ شفاعت کی اصل شفع یعنی زوج ہے.پس تمام
مدار شفاعت سے فیض اٹھانے کا اس بات پر ہے کہ جس شخص کی شفاعت سے مستفیض ہونا
چاہتا ہے اُس سے فطرتی تعلق اُس کو حاصل ہو، تا جو کچھ اس کی فطرت کو دیا گیا ہے اس کی
فطرت کو بھی وہی ملے یہ تعلق جیسا کہ وہی طور پر انسانی فطرت میں موجود ہے کہ ایک انسان
دوسرے انسان کی ایک جز ہے ایسا ہی کسی طور پر بھی یہ تعلق زیادت پذیر ہے یعنی جب ایک
انسان یہ چاہتا ہے کہ جو فطرتی محبت اور فطرتی ہمدردی بنی نوع کی اس میں موجود ہے اس میں
زیادت ہو تو اس میں بقدر دائرہ فطرت اور مناسبت کے زیادت بھی ہو جاتی ہے اسی بنا پر قوتِ
عشقی کا تموج بھی ہے کہ ایک شخص ایک شخص سے اس قدر محبت بڑھاتا ہے کہ بغیر اس کے
دیکھنے کے آرام نہیں کر سکتا.آخر اس کی شدت محبت اس دوسرے شخص کے دل پر بھی اثر کرتی
ہے اور جو شخص انتہا درجہ پر کسی سے محبت کرتا ہے وہی شخص کامل طور پر اور سچے طور پر اس کی
بھلائی کو بھی چاہتا ہے چنانچہ یہ امر بچوں کی نسبت ان کی ماؤں کی طرف سے مشہود اور محسوس
ہے.پس اصل جڑ شفاعت کی یہی محبت ہے جب اس کے ساتھ فطرتی تعلق بھی ہو کیونکہ بجز
فطرتی تعلق کے محبت کا کمال جو شرط شفاعت ہے غیر ممکن ہے اس تعلق کو انسانی فطرت میں
داخل کرنے کے لئے خدا نے حوا کو علیحدہ پیدا نہ کیا بلکہ آدم کی پسلی سے ہی اس کو نکالا.جیسا کہ
قرآن شریف میں فرمایا ہے : وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا (النِّساء 2) یعنی آدم کے وجود میں سے
ہی ہم نے اس کا جوڑا پیدا کیا جو حوا ہے.تا آدم کا یہ تعلق حوا اور اس کی اولاد سے طبعی ہو نہ
بناوٹی.اور یہ اس لئے کیا کہ تا آدم زادوں کے تعلق اور ہمدردی کو بقا ہو کیونکہ طبعی تعلقات
غیر منفک ہوتے ہیں مگر غیر طبعی تعلقات کے لئے بقا نہیں ہے کیونکہ ان میں وہ باہمی کشش
320
Page 329
نہیں ہے جو طبعی میں ہوتی ہے.غرض خدا نے اس طرح پر دونوں قسم کے تعلق جو آدم کے
لئے خدا سے اور بنی نوع سے ہونے چاہئے تھے طبعی طور پر پیدا کئے.پس اس تقریر سے صاف
ظاہر ہے کہ کامل انسان جو شفیع ہونے کے لائق ہو، وہی شخص ہو سکتا ہے جس نے ان دونوں
تعلقوں سے کامل حصہ لیا ہو اور کوئی شخص بجز ان ہر دو قسم کے کمال کے، انسان کامل نہیں ہو
سکتا.اسی لئے آدم کے بعد یہی سنت اللہ ایسے طرح پر جاری ہوئی کہ کامل انسان کے لئے جو
شفیع ہوسکتا ہے یہ دونوں تعلق ضروری ٹھہرائے گئے یعنی ایک یتعلق کہ ان میں آسمانی روح
پھونکی گئی اور خدا نے ایسا ان سے اتصال کیا کہ گویا ان میں اُتر آیا اور دوسرے یہ کہ بنی نوع کی
زوجیت کا وہ جوڑ جو حوا اور آدم میں باہمی محبت اور ہمدردی کے ساتھ مستحکم کیا گیا تھا ان میں
سب سے زیادہ چمکایا گیا.اسی تحریک سے ان کو بیویوں کی طرف بھی رغبت ہوئی اور یہی ایک
اوّل علامت اس بات کی ہے کہ ان میں بنی نوع کی ہمدردی کا مادہ ہے اور اسی کی طرف وہ
حدیث اشارہ کرتی ہے جس کے یہ الفاظ ہیں کہ خَیرُكُمْ خَيْرُ كُمْ بِأَهْلِهِ یعنی تم میں سے سب
سے زیادہ بنی نوع کے ساتھ بھلائی کرنے والا وہی ہوسکتا ہے کہ پہلے اپنی بیوی کے ساتھ بھلائی
کرے.مگر جو شخص اپنی بیوی کے ساتھ ظلم اور شرارت کا برتاؤ رکھتا ہے ممکن نہیں کہ وہ دوسروں
کے ساتھ بھی بھلائی کر سکے کیونکہ خدا نے آدم کو پیدا کر کے سب سے پہلے آدم کی محبت کا
مصداق اس کی بیوی کو ہی بنایا ہے.پس جو شخص اپنی بیوی سے محبت نہیں کرتا اور یا اس کی خود
بیوی ہی نہیں وہ کامل انسان ہونے کے مرتبہ سے گرا ہوا ہے اور شفاعت کی دو شرطوں میں سے
ایک شرط اس میں مفقود ہے.اس لئے اگر عصمت اس میں پائی بھی جائے تب بھی وہ شفاعت
کرنے کے لائق نہیں لیکن جو شخص کوئی بیوی نکاح میں لاتا ہے وہ اپنے لئے بنی نوع کی ہمدردی
کی بنیاد ڈالتا ہے کیونکہ ایک بیوی بہت سے رشتوں کا موجب ہو جاتی ہے اور بچے پیدا ہوتے ہیں
ان کی بیویاں آتی ہیں اور بچوں کی نانیاں اور بچوں کے ماموں وغیرہ ہوتے ہیں اور اس طرح پر
ایسا شخص خواہ مخواہ محبت اور ہمدردی کا عادی ہو جاتا ہے اور اس کی اس عادت
کا دائرہ وسیع ہو کر سب کو
321
Page 330
اپنی ہمدردی سے حصہ دیتا ہے لیکن جولوگ جوگیوں کی طرح نشو نما پاتے ہیں ان کو اس عادت کے
وسیع کرنے کا کوئی موقع نہیں ملتا.اس لئے ان کے دل سخت اور خشک رہ جاتے ہیں.اور عصمت کو شفاعت سے کوئی حقیقی تعلق نہیں کیونکہ عصمت کا مفہوم صرف اس حد تک ہے
کہ انسان گناہ سے بچے اور گناہ کی تعریف یہ ہے کہ انسان خدا کے حکم کو عمداً توڑ کر لائق سزا
ٹھہرے.پس صاف ظاہر ہے کہ عصمت اور شفاعت میں کوئی تلازم ذاتی نہیں کیونکہ تعریف
مذکورہ بالا کے رو سے نابالغ بچے اور پیدائشی مجنوں بھی معصوم ہیں وجہ یہ کہ وہ اس لائق نہیں ہیں کہ
کوئی گناہ عمدا کریں اور نہ وہ خدا تعالیٰ کے نزدیک کسی فعل کے ارتکاب سے قابل سزا
ٹھہرتے ہیں.پس بلاشبہ وہ حق رکھتے ہیں کہ ان کو معصوم کہا جائے مگر کیا وہ یہ حق بھی رکھتے ہیں
کہ وہ انسانوں کے شفیع ہوں اور منجی کہلائیں پس اس سے صاف ظاہر ہے کہ میجی ہونے اور
معصوم ہونے میں کوئی حقیقی رشتہ نہیں اور ہر گز عقل سمجھ نہیں سکتی کہ عصمت کو شفاعت سے کوئی
حقیقی تعلق ہے.ہاں ! عقل اس بات کو خوب
سمجھتی ہے کہ شفیع کے لئے یہ ضروری ہے کہ مذکورہ
بالا دو قسم کے تعلق اس میں پائے جائیں اور عقل بلا ترددیہ حکم کرتی ہے کہ اگر کسی انسان میں یہ دو
صفتیں موجود ہوں کہ ایک خدا سے تعلق شدید ہو اور دوسری طرف مخلوق سے بھی محبت اور ہمدردی
کا تعلق ہو تو بلاشبہ ایسا شخص ان لوگوں کے لئے جنہوں نے عمداً اس سے تعلق نہیں توڑا، دلی
جوش سے شفاعت کرے گا اور وہ شفاعت اس کی منظور کی جائے گی کیونکہ جس شخص کی فطرت کو یہ
دو تعلق عطا کئے گئے ہیں ان کا لازمی نتیجہ یہی کہ وہ خدا کی محبت تامہ کی وجہ سے اس فیض کو کھینچے اور
پھر مخلوق کی محبت تامہ کی وجہ سے وہ فیض ان تک پہنچاوے اور یہی وہ کیفیت ہے جس کو
دوسرے لفظوں میں شفاعت کہتے ہیں.شخص شفیع کے لئے جیسا کہ ابھی میں نے بیان کیا ہے
ضروری ہے کہ خدا سے اس کو ایک ایسا گہرا تعلق ہو کہ گو یا خدا اس کے دل میں اترا ہوا ہو اور اس
کی تمام انسانیت مرکز بال بال میں لا ہو تی تجلی پیدا ہوگئی ہو اور اس کی روح پانی کی طرح گداز ہو
کر خدا کی طرف بہ نکلی ہو اور اس طرح پر الہی قرب کے انتہائی نقطہ پر جا پہنچی ہو.اور اسی طرح
شفیع کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ جس کے لئے وہ شفاعت کرنا چاہتا ہے اس کی ہمدردی میں
322
Page 331
اس کا دل اُڑا جاتا ہو ایسا کہ گویا عنقریب اس پر غشی طاری ہوگی اور گو یا شدت قلق سے اس کے
اعضا اس سے علیحدہ ہوتے جاتے ہیں اور اس کے حواس منتشر ہیں اور اس کی ہمدردی نے اس کو
اس مقام تک پہنچایا ہو کہ جو باپ سے بڑھ کر اور ماں سے بڑھ کر اور ہر ایک غمخوار سے بڑھ کر
ہے پس جبکہ یہ دونوں حالتیں اس میں پیدا ہو جائیں گی تو وہ ایسا ہوجائے گا کہ گویا وہ ایک طرف
سے لاہوت کے مقام سے مُفت ہے اور دوسری طرف ناسوت کے مقام سے بجفت تب دونوں
پلہ میزان کے اس میں مساوی ہوں گے.یعنی وہ مظہر لاہوت کامل بھی ہوگا اور مظہر ناسُوت کامل
بھی اور بطور برزخ دونوں حالتوں میں واقع ہوگا.اس طرح پر...اسی مقام شفاعت کی طرف
قرآن شریف میں اشارہ فرما کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شفیع ہونے کی شان میں فرمایا
ہے : دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ ادنى (النجم 10-9) یعنی یہ رسول خدا کی طرف چڑھا اور
جہاں تک امکان میں ہے خدا سے نزدیک ہوا اور قرب کے تمام کمالات کو طے کیا اور لاہوتی
مقام سے پورا حصہ لیا اور پھر ناسوت کی طرف کامل رجوع کیا یعنی عبودیت کے انتہائی نقطہ تک
اپنے تئیں پہنچایا اور بشریت کے پاک لوازم یعنی بنی نوع کی ہمدردی اور محبت سے جو ناسوتی کمال
کہلاتا ہے پورا حصہ لیا لہذا ایک طرف خدا کی محبت میں اور دوسری طرف بنی نوع کی محبت میں
کمال تام تک پہنچا.پس چونکہ وہ کامل طور پر خدا سے قریب ہوا اور پھر کامل طور پر بنی نوع سے
قریب ہوا اس لئے دونوں طرف کے مساوی قرب کی وجہ سے ایسا ہو گیا جیسا کہ دو قوسوں میں
ایک خط ہوتا ہے لہذاوہ شرط جو شفاعت کے لئے ضروری ہے اس میں پائی گئی اور خدا نے اپنے
کلام میں اس کے لئے گواہی دی کہ وہ اپنے بنی نوع میں اور اپنے خدا میں ایسے طور سے درمیان
ہے جیسا کہ وتر دو قوسوں کے درمیان ہوتا ہے.( عصمت انبیاء علیہم السلام، روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 655تا664)
ممکن ہے کہ اس جگہ کوئی شخص یہ سوال بھی پیش کرے کہ انسان کو شفاعت کی کیوں
ضرورت ہے اور کیوں جائز نہیں کہ ایک شخص براہ راست تو بہ اور استغفار کر کے خدا سے معافی
حاصل کر لے؟ اس سوال کا جواب قانونِ قدرت خود دیتا ہے کیونکہ یہ بات مسلّم ہے اور کسی کو
323
Page 332
اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ انسان بلکہ تمام حیوانات کی نسل کا سلسلہ شفاعت پر ہی چل رہا ہے
کیونکہ ہم ابھی لکھ چکے ہیں کہ شفاعت کا لفظ شفع سے نکلا ہے جس کے معنی بجفت ہے پس اس
میں کیا شک ہو سکتا ہے کہ تمام برکات تناسل شفع سے ہی پیدا ہوئے ہیں اور ہورہے ہیں.ایک انسان کے اخلاق اور قوت اور صورت دوسرے انسان میں اسی ذریعہ سے آجاتے ہیں
یعنی وہ ایک جوڑ کا ہی نتیجہ ہوتا ہے.ایسا ہی ایک حیوان جو دوسرے سے پیدا ہوتا ہے مثلاً
بکری، بیل، گدھا وغیرہ وہ تمام قومی جو ایک حیوان سے دوسرے حیوان میں منتقل ہوتے ہیں وہ
بھی درحقیقت ایک جوڑ کا ہی نتیجہ ہوتا ہے.پس یہی جوڑ جب ان معنوں سے لیا جاتا ہے کہ
ایک ناقص ایک کامل سے روحانی تعلق پیدا کر کے اس کی روح سے اپنی کمزوری کا علاج پاتا
ہے اور نفسانی جذبات سے محفوظ رہتا ہے تو اس جوڑ کا نام شفاعت ہے.جیسا کہ چاند سورج
کے مقابل ہو کر ایک قسم کا اتحا د اور جوڑ اس سے حاصل کرتا ہے تو معاً اس نور کو حاصل کر لیتا ہے
جو آفتاب میں ہے اور چونکہ اس روحانی جوڑ کو جو پُر محبت دلوں کو انبیاء کے ساتھ حاصل ہوتا ہے
اس جسمانی جوڑ سے ایک مناسبت ہے جو زید کو مثلاً اپنے باپ سے ہے اس لئے یہ روحانی
فیضیاب بھی خدا کے نزدیک اولاد کہلاتی ہے اور اس تولد کو کامل طور پر حاصل کرنے والے
و ہی نقوش اور اخلاق اور برکات حاصل کر لیتے ہیں جو نبیوں میں موجود ہوتے ہیں پس دراصل
یہی حقیقت شفاعت ہے اور جس طرح جسمانی شفع یعنی جوڑ کا یہ لازمہ ذاتی ہے کہ اولادمناسب
حال اس شخص کے ہوتی ہے جس سے یہ جوڑ کیا گیا ہے ایسا ہی روحانی شفع کا بھی خاصہ ہے.غرض یہی حقیقت شفاعت ہے کہ خدا کا قانون قدرت جسمانی اور روحانی اس طرح پر قدیم سے
واقع ہے کہ تمام برکات جوڑ سے ہی پیدا ہوتی ہیں صرف یہ فرق ہے کہ ایک قسم کو شفع کہا گیا
ہے اور دوسری قسم کا نام شفاعت رکھا گیا اور انسان کو جس طرح کہ سلسلہ تناسل کے محفوظ رکھنے
کے لئے شفع کی ضرورت ہے ایسا ہی روحانیت کا سلسلہ باقی رکھنے کے لئے شفاعت کی
ضرورت ہے اور خدا کے کلام نے دونوں قسموں کو بیان فرما دیا ہے.جیسا کہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ
324
Page 333
قرآن شریف میں یہ فرماتا ہے کہ خدا نے آدم کو جوڑا پیدا کیا اور پھر اس جوڑ اسے بہت سی
مخلوق مرد اور عورت پیدا کئے اور ایسا ہی فرماتا ہے کہ خدا نے زمین پر اپنا خلیفہ پیدا کیا جو آدم تھا
جس میں خدائی روح تھی پھر وہ نور آدم سے دوسرے نبیوں میں منتقل ہوتا گیا اور ابراہیم اور
اسحاق اور اسماعیل اور یعقوب اور موسیٰ اور داؤد اور عیسیٰ وغیرہ سب اس نور کے وارث ہوئے
یہاں تک کہ آخری وارث ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے.پس ان تمام پاک نبیوں
نے جیسا کہ آدم سے وراثت میں جسمانی نقوش پائے ایسا ہی بحیثیت خلیفہ ہو نے آدم کے اُس سے
خدائی روح بھی پایا پھر ان کے ذریعہ سے وقتا فوقتا اور لوگ بھی وارث ہوتے گئے.( عصمت انبیاء علیهم السلام، روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 678تا680)
آخرت کا شفیع وہ ثابت ہو سکتا ہے جس نے دنیا میں شفاعت کا کوئی نمونہ دکھلایا ہو.سواس معیار کو آگے رکھ کر جب ہم موسیٰ پر نظر ڈالتے ہیں تو وہ بھی شفیع ثابت ہوتا ہے کیونکہ بار با
اس نے اُترتا ہوا عذاب دُعا سے ٹال دیا.اس کی توریت گواہ ہے اسی طرح جب ہم حضرت
محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر ڈالتے ہیں تو آپ کا شفیع ہونا اجلی بدیہیات معلوم ہوتا ہے
کیونکہ آپ کی شفاعت کا ہی اثر تھا کہ آپ نے غریب صحابہ کو تخت پر بٹھا دیا اور آپ کی
شفاعت کا ہی اثر تھا کہ وہ لوگ باوجود اس کے کہ بت پرستی اور شرک میں نشو و نما پایا تھا ایسے
موحد ہو گئے جن کی نظیر کسی زمانہ میں نہیں ملتی اور پھر آپ کی شفاعت کا ہی اثر ہے کہ اب تک
آپ کی پیروی کرنے والے خدا کا سچا الہام پاتے ہیں خدا ان سے ہم کلام ہوتا ہے مگر
مسیح ابن مریم میں یہ تمام ثبوت کیوں کر اور کہاں سے مل سکتے ہیں.ہمارے سید و مولیٰ محمد مصطفی
صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر اس سے بڑھ کر اور زبردست شہادت کیا ہوگی کہ ہم اس جناب
کے واسطے سے جو کچھ خدا سے پاتے ہیں ہمارے دشمن وہ نہیں پاسکتے اگر ہمارے مخالف اس
امتحان کی طرف آویں تو چند روز میں فیصلہ ہوسکتا ہے.( عصمت انبیاء علیہم السلام، روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 700،699)
تمام آدم زادوں کے لئے اب کوئی رسول اور شفیع نہیں مگرمحمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم.(کشتی نوح، روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 13 )
325
Page 334
جو شخص مجھ سے سچی بیعت کرتا ہے اور سچے دل سے میرا پیر و بنتا ہے اور میری اطاعت
میں محو ہو کر اپنے تمام ارادوں کو چھوڑتا ہے وہی ہے جو ان آفتوں کے دنوں میں میری رُوح
اُس کی شفاعت کرے گی.(کشتی نوح، روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 14 ،15)
وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ یعنی
خدا کی کرسی کے اندر تمام زمین و آسمان سمائے ہوئے ہیں اور وہ اُن سب کو اٹھائے ہوئے ہے.ان کے اٹھانے سے وہ تھکتا نہیں ہے اور وہ نہایت بلند ہے کوئی عقل اس کی گنہ تک پہنچ نہیں
سکتی اور نہایت بڑا ہے اس کی عظمت کے آگے سب چیزیں بیچ ہیں.یہ ہے ذکر کرسی کا اور یہ
محض ایک استعارہ ہے جس سے یہ جتلانا منظور ہے کہ زمین و آسمان سب خدا کے تصرف میں
ہیں اور ان سب سے اس کا مقام دور تر ہے اور اس کی عظمت نا پیدا کنار ہے.چشمه معرفت، روحانی خزائن جلد 23 صفحہ 118 حاشیہ)
وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وہ نہایت بزرگ اور صاحب عظمت ہے.ست بچن، روحانی خزائن جلد 10 صفحه (221)
لَا إِكْرَاءَ فِي الدِّينِ قَد تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْعَى فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ
وَيُؤْمِنُ بِاللهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ
سَمِيعٌ عَلِيمٌ (البقره 257)
لا إكراه في الدِّينِ یعنی یہ دین کوئی بات جبر سے منوانا نہیں چاہتا بلکہ ہر ایک بات
کے دلائل پیش کرتا ہے.اسلامی اصول کی فلاسفی، روحانی خزائن جلد 10 صفحه 433)
خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ : لا إكراه في الدِّينِ یعنی دین اسلام میں جبر نہیں ہے ہاں !
عیسائی لوگ ایک زمانہ میں جبر آلوگوں کو عیسائی بناتے تھے مگر اسلام جب سے ظاہر ہوا وہ جبر
کے مخالف ہے.جبر ان لوگوں کا کام ہے جن کے پاس آسمانی نشان نہیں.مگر اسلام تو آسمانی
326
Page 335
نشانوں کا سمندر ہے.کسی نبی سے اس قدر معجزات ظاہر نہیں ہوئے جس قدر ہمارے نبی صلی اللہ
علیہ وسلم سے کیونکہ پہلے نبیوں کے معجزات اُن کے مرنے کے ساتھ ہی مر گئے مگر ہمارے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اب تک ظہور میں آرہے ہیں اور قیامت تک ظاہر ہوتے رہیں
گے جو کچھ میری تائید میں ظاہر ہوتا ہے دراصل وہ سب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
معجزات ہیں.مگر کہاں ہیں وہ پادری یا یہودی یا اور قومیں جوان نشانوں کے مقابل پرنشان
دکھلا سکتے ہیں؟ ہر گز نہیں ! ہر گز نہیں !! ہر گز نہیں !!! اگرچہ کوشش کرتے کرتے مر بھی جائیں
تب بھی، ایک نشان بھی دکھلا نہیں سکتے.کیونکہ ان کے مصنوعی خدا ہیں، سچے خدا کے وہ پیرو نہیں
ہیں.اسلام معجزات کا سمندر ہے اس نے کبھی جبر نہیں کیا اور نہ اس کو جبر کی کچھ ضرورت ہے.(حقیقۃ الوحی، روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 469،468)
اسلام نے کبھی جبر کا مسئلہ نہیں سکھایا.اگر قرآن شریف اور تمام حدیث کی کتابوں
اور تاریخ کی کتابوں کو غور سے دیکھا جائے اور جہاں تک انسان کے لئے ممکن ہے تدبر سے
پڑھا یا سنا جائے تو اس قدر وسعت معلومات کے بعد قطعی یقین کے ساتھ معلوم ہوگا کہ یہ
اعتراض کہ گویا اسلام نے دین کو جب اپھیلانے کے لئے تلوار اٹھائی ہے نہایت بے بنیاد اور
قابل شرم الزام ہے اور یہ ان لوگوں کا خیال ہے جنہوں نے تعصب سے الگ ہو کر قرآن اور
حدیث اور اسلام کی معتبر تاریخوں کو نہیں دیکھا بلکہ جھوٹ اور بہتان لگانے سے پورا پورا کام لیا
ہے.مگر میں جانتا ہوں کہ اب وہ زمانہ قریب آتا جاتا ہے کہ راستی کے بھوکے اور پیاسے ان
بہتانوں کی حقیقت پر مطلع ہو جائیں گے.کیا اس مذہب کو ہم جبر کا مذہب کہہ سکتے ہیں جس
کی کتاب، قرآن میں صاف طور پر یہ ہدایت ہے کہ : لا إكراه في التاينِ یعنی دین میں داخل
کرنے کے لئے جبر جائز نہیں.کیا ہم اس بزرگ نبی کو جبر کا الزام دے سکتے ہیں جس نے
مکہ معظمہ کے تیرہ برس میں اپنے تمام دوستوں کو دن رات یہی نصیحت دی کہ شر کا مقابلہ مت کرو
اور صبر کرتے رہو.ہاں ! جب دشمنوں کی بدی حد سے گزرگئی اور دین اسلام کے مٹادینے کے
لئے تمام قوموں نے کوشش کی تو اس وقت غیرت الہی نے تقاضا کیا کہ جولوگ تلوار اٹھاتے
327
Page 336
ہیں وہ تلوار ہی سے قتل کئے جائیں ورنہ قرآن شریف نے ہر گز جبر کی تعلیم نہیں دی.اگر جبر کی
تعلیم ہوتی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جبر کی تعلیم کی وجہ سے اس لائق نہ ہوتے
کہ امتحانوں کے موقع پر سچے ایمانداروں کی طرح صدق دکھلا سکتے.لیکن ہمارے سید و مولی نبی
صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی وفاداری ایک ایسا امر ہے کہ اس کے اظہار کی ہمیں ضرورت
نہیں.یہ بات کسی پر پوشیدہ نہیں کہ ان سے صدق اور وفاداری کے نمونے اس درجہ پر ظہور
میں آئے کہ دوسری قوموں میں ان کی نظیر ملنا مشکل ہے.اس وفادار قوم نے تلواروں کے
نیچے بھی اپنی وفاداری اور صدق کو نہیں چھوڑا بلکہ اپنے بزرگ اور پاک نبی کی رفاقت میں وہ
صدق دکھلایا کہ کبھی انسان میں وہ صدق نہیں آسکتا جب تک ایمان سے اس کا دل اور سینہ منور
نہ ہو.غرض اسلام میں جبر کو دخل نہیں.اسلام کی لڑائیاں تین قسم سے باہر نہیں ؛ (1) دفاعی
طور پر یعنی بطریق حفاظت خود اختیاری (2) بطور سزا یعنی خون کے عوض میں خون، (3) بطور
آزادی قائم کرنے کے یعنی بغرض مزاحموں کی قوت توڑنے کے جو مسلمان ہونے پر قتل
کرتے تھے.پس جس حالت میں اسلام میں یہ ہدایت ہی نہیں کہ کسی شخص کو جبر اور قتل کی
دھمکی سے دین میں داخل کیا جائے تو پھر کسی خونی مہدی یا خونی مسیح کی انتظار کرنا سراسر لغو اور
بیہودہ ہے.کیونکہ ممکن نہیں کہ قرآنی تعلیم کے برخلاف کوئی ایسا انسان بھی دنیا میں آوے جو
تلوار کے ساتھ لوگوں کو مسلمان کرے.☆
مسیح ہندوستان میں ، روحانی خزائن جلد 15 صفحه 11، 12 )
قرآن میں صاف حکم ہے کہ دین کے پھیلانے کے لئے تلوار مت اٹھاؤ اور دین کی
ذاتی خوبیوں کو پیش کرو اور نیک نمونوں سے اپنی طرف کھینچو اور یہ مت خیال کرو کہ ابتدا میں
اسلام میں تلوار کا حکم ہوا کیونکہ وہ تلوار دین کو پھیلانے کے لئے نہیں کھینچی گئی تھی بلکہ دشمنوں کے
حملوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لئے اور یا امن قائم کرنے کے لئے کھینچی گئی تھی مگر دین کے
لئے جبر کرنا کبھی مقصد نہ تھا.ستاره قیصریه، روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 120 ، 121 )
تمام سچے مسلمان جودنیا میں گزرے کبھی ان
کا یہ عقیدہ نہیں ہوا کہ اسلام کو تلوار سے
328
Page 337
پھیلانا چاہئے بلکہ ہمیشہ اسلام اپنی ذاتی خوبیوں کی وجہ سے دنیا میں پھیلا ہے.پس جولوگ
مسلمان کہلا کر صرف یہی بات جانتے ہیں کہ اسلام کو تلوار سے پھیلانا چاہئے وہ اسلام کی ذاتی
خوبیوں کے معترف نہیں ہیں اور ان کی کارروائی درندوں کی کارروائی سے مشابہ ہے.تریاق القلوب، روحانی خزائن جلد 15 صفحه 167 حاشیہ )
یہ جہالت اور سخت نادانی ہے کہ اس زمانہ کے نیم مثلا فی الفور کہہ دیتے ہیں کہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جبراً مسلمان کرنے کے لئے تلوار اٹھائی تھی اور انہی شبہات
میں نا سمجھ پادری گرفتار ہیں.مگر اس سے زیادہ کوئی جھوٹی بات نہیں ہوگی کہ یہ جبر اور تعدی کا
الزام اس دین پر لگایا جائے جس کی پہلی ہدایت یہی ہے کہ : لا اکراہ فی الدین یعنی دین
میں جبر نہیں چاہئے بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بزرگ صحابہ کی لڑائیاں یا تو
اس لئے تھیں کہ کفار کے حملہ سے اپنے تئیں بچایا جائے اور یا اس لئے تھیں کہ امن قائم کیا
جائے اور جولوگ تلوار سے دین کو روکنا چاہتے ہیں ان کو تلوار سے پیچھے ہٹایا جائے.تریاق القلوب، روحانی خزائن جلد 15 صفحه 158)
لا إكراه في الدين یعنی دین کو جبر سے شائع نہیں کرنا چاہئے.تریاق القلوب، روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 519)
جس کتاب میں یہ آیت اب تک موجود ہے کہ : لا اکراہ فی الدین یعنی دین کے
معاملہ میں زبر دستی نہیں کرنی چاہئے.کیا اس کی نسبت ہم ظن کر سکتے ہیں کہ وہ جہاد کی تعلیم دیتی ہے؟
گورنمنٹ انگریزی اور جہاد، روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 32)
جس کام کے لئے آپ لوگوں کے عقیدوں کے موافق مسیح ابن مریم آسمان سے آئے گا
یعنی یہ کہ مہدی سے مل کر لوگوں کو جبر مسلمان کرنے کے لئے جنگ کرے گا یہ ایک ایسا عقیدہ
ہے جو اسلام کو بدنام کرتا ہے.قرآن شریف میں کہاں لکھا ہے کہ مذہب کے لئے جبر
درست ہے؟ بلکہ اللہ تعالیٰ تو قرآن شریف میں فرماتا ہے : لا اکراہ فی الدین یعنی دین میں
جبر نہیں ہے پھر مسیح ابن مریم کو جبر کا اختیار کیوں کر دیا جائے گا یہاں تک کہ بجز اسلام یا قتل
کے جزیہ بھی قبول نہ کرے گا یہ تعلیم قرآن شریف کی کس مقام اور کس سیپارہ اور کس سورہ میں
329
Page 338
ہے؟ سارا قرآن بار بار کہ رہا ہے کہ دین میں جبر نہیں اور صاف طور پر ظاہر کر رہا ہے کہ جن
لوگوں سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت لڑائیاں
کی گئی تھیں وہ لڑائیاں دین کو جبر آشائع
کرنے کے لئے نہیں تھیں بلکہ یا تو بطور سزا تھیں یعنی اُن لوگوں کو سزا دینا منظور تھا جنہوں نے
ایک گروہ کثیر مسلمانوں کو قتل کر دیا اور بعض کو وطن سے نکال دیا تھا اور نہایت سخت ظلم کیا تھا
جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے : أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقْتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوْاوَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ
لقَدِيرُ (الحج (40) یعنی ان مسلمانوں کو جن سے کفار جنگ کر رہے ہیں بسبب مظلوم ہونے کے
مقابلہ کرنے کی اجازت دی گئی اور خدا قادر ہے کہ جو ان کی مدد کرے.اور یا وہ لڑائیاں ہیں جو
بطور مدافعت تھیں یعنی جو لوگ اسلام کے نابود کرنے کے لئے پیش قدمی کرتے تھے یا اپنے
ملک میں اسلام کو شائع ہونے سے جبراً روکتے تھے ان سے بطور حفاظت خود اختیاری یا ملک
میں آزادی پیدا کرنے کے لئے لڑائی کی جاتی تھی بجز ان تین صورتوں کے آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم اور آپ کے مقدس خلیفوں نے کوئی لڑائی نہیں کی بلکہ اسلام نے غیر قوموں کے ظلم کی
اس قدر برداشت کی ہے جو اس کی دوسری قوموں میں نظیر نہیں ملتی پھر یہ عیسی مسیح اور مہدی
صاحب کیسے ہوں گے جو آتے ہی لوگوں کو قتل کرنا شروع کردیں گے یہاں تک کہ کسی اہل
کتاب سے بھی جزیہ قبول نہیں کریں گے اور آیت : حتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَهُمْ صَغِرُونَ
(التوبة (29) کو بھی منسوخ کر دیں گے.یہ دین اسلام کے کیسے حامی ہوں گے کہ آتے ہی
قرآن کی ان آیتوں کو بھی منسوخ کر دیں گے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی
منسوخ نہیں ہوئیں اور اس قدر انقلاب سے پھر بھی ختم نبوت میں حرج نہیں آئے گا.اس
زمانہ میں جو تیرہ سو برس عہد نبوت کو گزر گئے اور خود اسلام اندرونی طور پر تہتر فرقوں پر پھیل
گیا.سچے مسیح کا یہ کام ہونا چاہئے کہ وہ دلائل کے ساتھ دلوں پر فتح پاوے نہ تلوار کے ساتھ اور صلیبی
عقیدہ کو واقعی اور سچے ثبوت کے ساتھ توڑ دے نہ یہ کہ اُن صلیبوں کو توڑتا پھرے جو چاندی یا
سونے یا پیتل یا لکڑی سے بنائی جاتی ہیں.اگر تم جبر کرو گے تو تمہارا جبر اس بات پر کافی دلیل
ہے کہ تمہارے پاس اپنی سچائی پر کوئی دلیل نہیں، ہر یک نادان اور ظالم طبع جب دلیل سے
330
Page 339
عاجز آ جاتا ہے تو پھر تلوار یا بندوق کی طرف ہاتھ لمبا کرتا ہے مگر ایسا مذہب ہرگز ہرگز ! خدا تعالیٰ
کی طرف سے نہیں ہوسکتا جو صرف تلوار کے سہارے سے پھیل سکتا ہے نہ کسی اور طریق سے.اگر تم ایسے جہاد سے باز نہیں آ سکتے اور اس پر غصہ میں آکر راستبازوں کا نام بھی دجال اور ملحد
رکھتے ہو تو ہم ان دو فقروں پر اس تقریر کو ختم کرتے ہیں : قُلْ يَأْيُّهَا الْكَفِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا
تَعْبُدُونَ (الكافرون (3-2) اندرونی تفرقہ اور پھوٹ کے زمانہ میں تمہارا فرضی مسیح اور فرضی مہدی
کس کس پر تلوار چلائے گا؟ کیا سنیوں کے نزدیک شیعہ اس لائق نہیں کہ اُن پر تلوار اٹھائی
جائے ؟ اور شیعوں کے نزدیک سُستی اس لائق نہیں کہ ان سب کو تلوار سے نیست و نابود کیا
جاوے؟ پس جب کہ تمہارے اندرونی فرقے ہی تمہارے عقیدہ کی رُو سے مستوجب سزا ہیں تو
تم کس کس سے جہاد کرو گے؟ مگر یاد رکھو کہ خدا تلوار کا محتاج نہیں وہ اپنے دین کو آسمانی
نشانوں کے ساتھ زمین پر پھیلائے گا اور کوئی اُس کو روک نہیں سکے گا.(کشتی نوح ، روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 73 تا76 )
میں نہیں جانتا کہ ہمارے مخالفوں نے کہاں سے اور کس سے سن لیا کہ اسلام تلوار کے
زور سے پھیلا ہے.خدا تو قرآن شریف میں فرماتا ہے : لا إكراه في الدين یعنی دین اسلام
میں جبر نہیں.تو پھر کس نے جبر کا حکم دیا اور جبر کے کون سے سامان تھے؟ اور کیا وہ لوگ جو جبر
سے مسلمان کئے جاتے ہیں اُن کا یہی صدق اور یہی ایمان ہوتا ہے کہ بغیر کسی تنخواہ پانے کے
باوجود دو تین سو آدمی ہونے کے ہزاروں آدمیوں کا مقابلہ کریں اور جب ہزار تک پہنچ جائیں تو
کئی لاکھ دشمن کو شکست دے دیں اور دین کو دشمن کے حملہ سے بچانے کے لئے بھیڑوں
بکریوں کی طرح سر کٹا دیں اور اسلام کی سچائی پر اپنے خون سے مہریں کر دیں اور خدا کی توحید
کے پھیلانے کے لئے ایسے عاشق ہوں کہ درویشانہ طور پر سختی اٹھا کر افریقہ کے ریگستان تک
پہنچیں اور اس ملک میں اسلام کو پھیلا دیں اور پھر ہر یک قسم کی صعوبت اُٹھا کر چین تک
پہنچیں نہ جنگ کے طور پر بلکہ محض درویشانہ طور پر اور اس ملک میں پہنچ کر دعوتِ اسلام کریں
جس کا نتیجہ یہ ہو کہ اُن کے بابرکت وعظ سے کئی کروڑ مسلمان اس زمین میں پیدا ہوجائیں اور
331
Page 340
پھر ٹاٹ پوش درویشوں کے رنگ میں ہندوستان میں آئیں اور بہت سے حصہ آریہ ورت کو
اسلام سے مشرف کر دیں اور یورپ کی حدود تک لا إلهَ إِلَّا الله کی آواز پہنچاویں ؟ تم ایمانا
کہوا کہ کیا یہ کام ان لوگوں کا ہے جو جبر- امسلمان کئے جاتے ہیں جن کا دل کا فر اور زبان مومن
ہوتی ہے؟ نہیں! بلکہ یہ اُن لوگوں کے کام ہیں جن کے دل نور ایمان سے بھر جاتے ہیں اور جن
کے دلوں میں خدا ہی خدا ہوتا ہے.(پیغام صلح، روحانی خزائن جلد 23 صفحہ 468، 469)
یاد رکھو! مہدی کی نسبت جو حدیثیں ہیں جن میں لکھا ہے کہ وہ جنگ کرے گا اور خونریزی
کرے گا.ان کی نسبت خودان مولویوں نے لکھ دیا ہے کہ بہت سی حدیثیں ان میں موضوع ہیں
اور قریباً سب کی سب مجروح ہیں.ہمارا یہ مذہب نہیں ہے کہ مہدی آئے گا تو خون کرتا
پھرے گا وہ دین کیا ہوا جس میں سوائے جنگ اور جدال کے اور کچھ نہ ہو.جہاد کے مسئلہ کو بھی
ان ناواقفوں نے نہیں سمجھا.قرآن شریف تو کہتا ہے : لا اکراہ فی الدین تو کیا اگر مہدی آکر
لڑائیاں کرے گا تو اكراة في الدين جائز ہوگا اور قرآن شریف کے اس حکم کی بے حرمتی
ہوگی.اُس کے آنے کی غرض تو یہ ہے کہ وہ اسلام کو زندہ کرے یا یہ کہ اس کی توہین کرے.اگر
دین میں لڑائیاں ہی ضروری ہوتی ہیں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرہ برس تک مکہ میں رہ کر
کیوں نہ لڑے؟ ہر قسم کی تکلیف اٹھاتے رہے اور پھر بھی آپ نے ابتدا نہیں کی اور ہمارا
مذہب ہے کہ جبر مسلمان کرنے کے واسطے لڑائیاں ہر گز نہیں کی ہیں بلکہ وہ لڑائیاں خدا
تعالیٰ کا ایک عذاب تھا اُن لوگوں کے لئے جنہوں نے آپ کو سخت تکالیف دی تھیں اور
مسلمانوں کا تعاقب کیا اور اُن کو تنگ کیا تھا.پس یہ ہر گز صحیح نہیں ہے کہ اسلام تلوار دکھاتا
ہے.اسلام تو قرآن اور ہدایت پیش کرتا ہے.وہ صلح اور امن لے کر آیا ہے اور دنیا میں کوئی
ایسا مذہب نہیں جو اسلام کی طرح صلح پھیلاتا ہو.پس یہ غلط ہے کہ مہدی جنگ کرے گا.ہمارا
یہ مذہب ہر گز نہیں.بھلا اگر تلوار مارکرلوگوں کو بلاک کر دیا اور اُن کے املاک لوٹ لئے تو اس
سے فائدہ کیا ہوا؟ جس مہدی ہونے کا ہما را دعویٰ ہے یہ تو قرآن شریف سے ثابت ہے جیسے
332
Page 341
موسوی سلسله مسیح پر آ کر ختم ہوا اسی طرح خدا تعالیٰ نے ایک خاص مناسبت کی وجہ سے اس
سلسلہ کو بھی ایک محمدی مسیح پر ختم کیا ہے اور مہدی نام اس کا اس لئے رکھا ہے کہ وہ
براہ راست خدا تعالیٰ سے ہدایت پائے گا اور ایسے وقت میں آئے گا جبکہ دنیا سے نور و
ہدایت اُٹھ گئے ہوں گے.پھر ایک لطیف تر بات ان دونوں سلسلوں کی مماثلت میں یہ ہے کہ
جیسے مسیح موسوی موسیٰ علیہ السلام کے بعد چودھویں صدی) میں آیا تھا یہاں بھی مسیح محمدی کی
بعثت کا زمانہ چودھویں ہی صدی ہے اور جیسے مسیح موسوی یہودیوں کی سلطنت نہیں بلکہ
رومیوں کی سلطنت میں پیدا ہوا تھا اسی طرح محمدی مسیح بھی مسلمانوں کی سلطنت میں نہیں بلکہ
انگلش گورنمنٹ کی سلطنت میں پیدا ہوا ہے.غرض ہمارا ہر گز یہ مذہب نہیں ہے کہ مہدی آ کر
لڑائیاں کرتا پھرے گا اور خونریزی اُس کا کام ہوگا.الحکم جلد 5 نمبر 29 مؤرخہ 10 اگست 1901 ، صفحہ 8)
میں سچ کہتا ہوں کہ اگر نوح کی قوم کا اعتراض شریفانہ رنگ میں ہوتا تو اللہ تعالیٰ نہ پکڑتا.ساری قومیں اپنی کرتوتوں کی پاداش میں سزا پاتی ہیں.خدا تعالیٰ نے تو یہاں تک بھی فرما دیا ہے کہ
جولوگ قرآن سننے کے لئے آتے ہیں ان کو امن کی جگہ تک پہنچادیا جاوے خواہ وہ مخالف اور منکر ہی
ہوں، اس لئے کہ اسلام میں جبر اور اکران نہیں جیسے فرمایا : لا إكراه في الدين
الحکم جلد 6 نمبر 13 مورخہ 10 را پریل 1902 ، صفحہ 4)
وہ تمام لوگ آگاہ رہیں ! جو اسلام کے بزور شمشیر پھیلائے جانے کا اعتراض کرتے ہیں
کہ وہ اپنے اس دعوے میں جھوٹے ہیں.اسلام کی تاثیرات اپنی اشاعت کے لئے کسی جبر کی
محتاج نہیں ہیں.اگر کسی کو شک ہے تو وہ میرے پاس رہ کر دیکھ لے کہ اسلام اپنی زندگی کا
ثبوت براہین اور نشانات سے دیتا ہے....انگلستان اور فرانس اور دیگر ممالک یورپ میں یہ
الزام بڑی سختی سے اسلام پر لگایا جاتا ہے کہ وہ جبر کے ساتھ پھیلایا گیا ہے مگر افسوس اور سخت
افسوس ہے کہ وہ نہیں دیکھتے کہ اسلاملا اکراہ فی الدین کی تعلیم دیتا ہے اور انہیں نہیں معلوم
کہ کیا وہ مذہب جو فتح پا کر بھی گرجے نہ گرانے کا حکم دیتا ہے کیا وہ جبر کر سکتا ہے؟ مگر اصل
333
Page 342
بات یہ ہے کہ ان ملانوں نے جو اسلام کے نادان دوست ہیں، یہ فساد ڈالا ہے.انہوں نے
خود اسلام کی حقیقت کو سمجھا نہیں اور اپنے خیالی عقائد کی بنا پر دوسروں کو اعتراض کا موقعہ دیا.الحکم جلد 6 نمبر 16 مورخہ 30 را پریل 1902 صفحہ 6)
اب تلوار سے کام لینا تو اسلام پر تلوار مارنی ہے، اب تو دلوں کو فتح کرنے کا وقت ہے
اور یہ بات جبر سے نہیں ہو سکتی.یہ اعتراض کہ آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) نے پہلے تلوار
اُٹھائی بالکل غلط ہے، تیرہ برس تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ صبر کرتے رہے پھر
باوجود اس کے کہ دشمنوں کا تعاقب کرتے تھے مگر صلح کے خواستگار ہوتے تھے کہ کسی طرح جنگ
نہ ہو.اور جو مشرک قومیں صلح اور امن کی خواست گار ہوتیں ان کو امن دیا جاتا اور صلح کی جاتی
اسلام نے بڑے بڑے پیچوں سے اپنے آپ کو جنگ سے بچانا چاہا ہے.جنگ کی بنیاد کو خود
خدا تعالی بیان فرماتا ہے کہ چونکہ یہ لوگ بہت مظلوم ہیں اور ان کو ہر طرح سے دکھ دیا گیا ہے
اس لئے اب اللہ تعالیٰ اجازت دیتا ہے کہ یہ بھی ان کے مقابلہ پر لڑیں.ور نہ اگر تعصب ہوتا تو یہ حکم پہنچتا کہ مسلمانوں کو چاہئے کہ دین کی اشاعت کے واسطے جنگ
کریں.لیکن ادھر حکم دیا کہ ( لا احتراة في الدين یعنی دین میں کوئی زبردستی نہیں ) اور ادھر
جب غایت درجہ کی سختی اور ظلم مسلمانوں پر ہوئے تو پھر مقابلہ کا حکم دیا.البدر جلد اوّل نمبر 10 مورخہ 2 جنوری 1903 ، صفحہ 74)
مذہبی امور میں آزادی ہونی چاہئے.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے : لا إكراه في الدِّينِ کہ
دین میں کسی قسم کی زبردستی نہیں ہے.اس قسم کا فقرہ انجیل میں کہیں بھی نہیں ہے.لڑائیوں کی
اصل جڑھ کیا تھی؟ اس کے سمجھنے میں ان لوگوں سے غلطی ہوئی ہے.اگر لڑائی کا ہی حکم تھا تو تیرہ
برس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو پھر ضائع ہی گئے کہ آپ نے آتے ہی تلوار نہ اٹھائی.صرف لڑنے والوں کے ساتھ لڑائیوں کا حکم ہے.اسلام کا یہ اصول کبھی نہیں ہوا کہ خود ابتدائے
جنگ کریں.لڑائی کا کیا سبب تھا؟ اسے خود خدا نے بتلایا ہے کہ ظلموا.خدا نے جب دیکھا
کہ یہ لوگ مظلوم ہیں تو اب اجازت دیتا ہے کہ تم بھی لڑو.یہ نہیں حکم دیا کہ اب وقت تلوار کا
334
Page 343
ہے تم زبر دستی تلوار کے ذریعہ لوگوں کو مسلمان کرو.بلکہ یہ کہا کہ تم مظلوم ہو، اب مقابلہ کرو.مظلوم کو تو ہر ایک قانون اجازت دیتا ہے کہ حفظ جان کے واسطے مقابلہ کرے.( البدر جلد 2 نمبر 1 ، 2 مورخہ 23 و 30 جنوری 1903 ، صفحہ 3)
یہ اعتراض کہ اگر جہاد اب جائز نہیں تو اسلام میں اول زمانہ میں کیوں تلوار سے کام لیا
گیا؟ یہ معترضین کی اپنی غلطی ہے جو باعث ناواقفیت پیدا ہوئی ہے.انہیں معلوم نہیں کہ
اسلام دین کے پھیلانے کے لئے ہرگز جبر کی اجازت نہیں دیتا.دیکھو کیسی ممانعت قرآن
میں موجود ہے کہ فرماتا ہے کہ : لا اکراه فی الدین یعنی دین میں جبر نہیں کرنا چاہئے.( گناہ سے نجات کیونکر مل سکتی ہے.روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 631)
الله ولى الذين امنوا تُخرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ
كَفَرُوا أَوْلِيَهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمتِ
أوليك أصْحَبُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خُلِدُونَ (البقرة 258)
اللہ دوست دار ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے اور ان کو اندھیرے سے روشنی کی طرف
نکالتا ہے.( جنگ مقدس، روحانی خزائن جلد 6 صفحه 87)
خدا سے پورے طور پر ڈرنا بجز یقین کے کبھی ممکن نہیں.تقویٰ کی باریک راہوں پر قدم
مارنا اور اپنے عمل کو ریا کاری کی ملونی سے پاک کر دینا بجز یقین کے
کبھی ممکن نہیں.ایسا ہی دنیا
کی دولت اور حشمت اور اس کی کیمیا پر لعنت بھیجنا اور بادشاہوں کے قرب سے بے پرواہ ہو
جانا اور صرف خدا کو اپنا ایک خزانہ سمجھنا بجز یقین کے ہرگز ممکن نہیں.اب بتلاؤ، اے مسلمان
کہلانے والو! کہ ظلمات شک سے نوریقین کی طرف تم کیونکر پہنچ سکتے ہو؟ یقین کا ذریعہ تو خدا
تعالیٰ کا کلام ہے جو يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمتِ إِلَى النُّوْرِ کا مصداق ہے.( نزول المسیح، روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 470)
بعض لوگوں کا خیال ہے کہ بہت نیکیاں کرنے سے انسان ولی بنتا ہے.یہ نادانی
335
Page 344
ہے.مومن کو تو خدا نے اول ہی ولی بنایا ہے.جیسے کہ فرمایا ہے : اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا.( البدر جلد 4 نمبر 3 مورخہ 20 جنوری 1905 ، صفحہ 3)
(ماخوذ از تفسیر حضرت مسیح موعود علیہ السلام )
حضرت خلیفتہ المسیح الاوّل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:
يَوْمٌ لا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةُ : ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ وہاں نہ کوئی نئی
بیچ ہو سکے گی نہ خلت ، نہ شفاعت.یہاں بیع، خلت ، شفاعت کی مطلق نفی ہر گز نہیں ہے.عربی میں لا دو طرح کے آتے ہیں.ایک وہ جس کے بعد تنوین آتی ہے اور ایک وہ جس کے
بعد تنوین نہیں آتی.پہلے کی مثال یہی آیت ہے.اور دوسرے کہ مثال لا رَفَتَ وَلَا فُسُوقَ وَ
لا جدال (البقرة 198) ان دونوں لا میں فرق ہے.تنوین نہ ہو تو اس کے معنی ہیں ”بالکل نہیں“.لا نفی جنس کا ہے اور اگر تنوین ہو تو اس سے
مراد ہے بعض صورتوں میں نہیں.یہ لا، مشبہ بہ لیس ہے.اب چونکہ یہاں تنوین ہے اس
لئے یہاں بیع کی مطلق نفی نہیں.اسی لئے دوسرے مقام پر فرمایا فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ
الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ (التوبه (111) اور نہ خُلَّة کی مطلق نفی ہے.چنانچہ فرمایا الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ
بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ (الزخرف 68) اور نہ شفاعت کی چنانچہ اس سے آگے اِلَّا
باذنہ آتا ہے.وَالْكَفِرُونَ هُمُ الظَّلِمُونَ: کافر اپنی جان پر بھی ظلم کرتا ہے اور دوسروں پر بھی.اخبار بدر قادیان 6 مئی 1909ء)
ہر ایک عیب سے پاک.تمام صفات کاملہ کے ساتھ موصوف.جس کا نام ہے اللہ.اس کے بغیر کوئی بھی پرستش و فرمانبرداری کا مستحق نہیں.دائم اور باقی تمام موجودات کا مدبر
اور حافظ جس کو کبھی سستی ، اُونگھ اور نیند نہ ہو.اُسی کے تصریف اور ملک اور خلق میں ہیں.آسمان و زمین اُسی کی ہستی اور یکتائی کو ثابت کرتے ہیں.کوئی بھی نہیں کہ اس کی کبریائی،
336
Page 345
عظمت کے باعث اس پاک ذات کی پروانگی کے سوا کسی کی سپارش بھی کر سکے.پس کسی کو
مقابلہ وحمایت کی تو کیا سکت ہوگی.وہ جانتا ہے تمام جو کچھ آگے ہوگا اور جو کچھ گذر چکا ہے.موجودات کی نسبت کیا کہنا ہے.کوئی بھی اس کے علم سے کسی چیز کا اس کی مشیت کے سوا
احاطہ نہیں کر سکتا.اس کا کامل علم آسمانوں اور زمینوں پر حاوی ہے اور وہ آسمانوں اور زمینوں کی
حفاظت سے کبھی نہیں تھکتا.وہ شریک اور جوڑ سے بلند ہے.صحیح بخاری میں جسے ہم کتاب اللہ کے بعد اصح الکتب مانتے ہیں لکھا ہے گُرسِيُّهُ
عِلمه یعنی کرسی کے معنے علم کے ہیں.پس معنی کُرسِيُّهُ السَّمَوتِ وَالْأَرْضَ (البقرة 256)
یہ ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کا علم تمام بلندیوں اور زمینوں کو وسیع اور محیط ہورہا ہے.لَا إِكْرَاةَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرُ
بالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى
لا انفِصَامَ لَهَا وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.لا إكراه في الدين : ایک انبیاء کی راہ ہوتی ہے.ایک بادشاہوں کی.انبیاء کا یہ قاعدہ نہیں
ہوتا کہ وہ ظلم و جور و تعدی سے کام لیں.ہاں بادشاہ جبر وا کراہ سے کام لیتے ہیں.اللہ تعالیٰ
فرماتا ہے کہ جبر و اکراہ کا تعلق مذہب سے نہیں.پس کسی کو جبر سے مت داخل کرو کیونکہ جو
دل سے مومن نہیں ہوا وہ ضرور منافق ہے.پھر اسلام بادشاہوں کے افعال کا ذمہ دار نہیں.مسلمانوں نے یہی غلطی کی کہ معترضین
کے مفتریات کو تسلیم کر لیا حالانکہ اسلام دلی محبت و اخلاق سے حق بات ماننے کا نام ہے.اسی
لئے اسلام میں جبر نہیں.یہ آیت ضروری یا درکھنی چاہئے.اسلام میں ہر گزرا کراہ نہیں.قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَي
رُشد کہتے ہیں اصَابَةُ الْحَقِّ وَالضَّوَابِ یعنی واقعی بات کو پالینا اور حق تک پہنچ جانا.غی کہتے ہیں اس حق وصواب کی جگہ سے رُک جانے کو.337
Page 346
فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ
طاغوت طَعورت سے نکلا ہے.حد بندی سے آگے بڑھنے والے کو طافی کہتے ہیں.سیلاب کو بھی طغیانی اِسی لئے کہتے ہیں کہ پانی ندی کی حد مقررہ سے
باہر نکل کر اُچھلتا ہے.شریعت نے ہر بات کے لئے حد رکھی ہے پس جو اس حد سے نکلا ہے وہ طاغی ہوا اور جو
تمام حد بندیوں کو توڑ کر نکل جاوے وہ طاغوت کہلاتا ہے.پس جو حضرت حق سبحانہ کا، جو
منز ہ ہے تمام عیوب و نقائص سے اور جامع ہے کمالات وخوبیوں کا ، فرمانبردار ہوتو فقد
اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى اُس نے بڑی مضبوط پکڑنے کی چیز کو پکڑا.عُروہ کہتے ہیں
پکڑنے کی چیز کو.لا إكراه في الدِّينِ قَد أَمَانَ الرُّشْدُ مِنَ التي
دین کے معاملہ میں جبر نہیں.رشد اور غنی الگ الگ چیزیں ہیں.رشد اختیار کرنے اور غنی کے چھوڑنے میں کسی اکراہ کی
ضرورت نہیں.اس آیت میں تین لفظ ہیں.دین رشد اور غی.الدين: اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں جو دین کی توضیح اور تفسیر فرمائی ہے وہ یہ ہے ان
الدين عند الله الاسلام اللہ تعالیٰ کے حضور دین کی حقیقت اور ماہیت کیا ہے؟
الإسلام اپنی ساری قوتوں اور طاقتوں کے ساتھ اللہ تعالی کا فرمانبردار ہو جائے.اللہ تعالیٰ
کے فرمان کو لے اور اس پر روح اور راستی سے عمل درآمد کرے.دین کے متعلق جبرائیل
علیہ السّلام نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور سوال کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم
نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بلکہ ہم کو آگاہ کیا ہے کہ یہ جبرائیل تھا.آتَاكُمْ لِيُعَلِّمَكُمْ
دِينَكُمْ.پس دین کی حقیقت اور اس کا صحیح اور سچا مفہوم وہ ہوگا جو آ نحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے اس وقت بیان فرمایا.الاسلام کے معنے یہ ہیں.سر رکھ دینا.جان سے.دل سے.اعضاء سے.مال سے.غرض ہر پہلو اور ہر حالت میں اللہ تعالیٰ ہی کی فرمانبرداری کرنا.338
Page 347
دین کے لئے اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزیں عطا فرمائی ہیں جن کے ذریعہ ہم اس کی کامل
اطاعت، فرمان پذیری اور وفاداری کا اظہار کر سکتے ہیں اور پھر ان کے وراء الورا اندر ہی اندر
قویٰ پر حکمرانی کر سکتے ہیں اور ان کو الہی فرمانبرداری میں لگا سکتے ہیں.غرض دین کی اصل
حقیقت جو قرآن شریف نے بتائی ہے وہ مختصر الفاظ میں کامل وفاداری ، بیٹی اطاعت اور اللہ
تعالیٰ کی فرمانبرداری ہے.قوانین اسلام کے موافق ہر قسم کی آزادی مذہبی اور مذہب والوں کو بخشی گئی جو سلطنت
اسلام کے مطیع و محکوم تھے.لا إكراه في الدِّينِ ( البقرة257) دین میں کوئی اجبار نہیں.یہ
آیت گھلی دلیل اس امر کی ہے کہ اسلام میں اور اہل مذاہب کو آزادی بخشنے اور ان کے ساتھ
نیکی کرنے کا حکم ہے.اسلام کے معنے ضلع کے ساتھ زندگی بسر کرنا، چین سے رہنا.کیونکہ یہ لفظ سلم سے مشتق ہے
جس کے معنے صلح اور آشتی کے ہیں.جبر و اکراہ سے اسلام اور تصدیق قلبی کا حصول ممکن نہیں.اسلام میں شرط ہے کہ آدمی صدق دل سے باری تعالیٰ کی الوہیت اور اس کی معبودیت اور
اس کے رسولوں کی رسالت وغیرہ وغیرہ ضروریات دین پر یقین لاوے تب مسلمان کہلاوے اور
ظاہر ہے کہ دلی یقین جبر و اکراہ سے کبھی ممکن نہیں ہے.میں بڑی جرأت سے کہتا ہوں کہ
حضور علیہ السّلام اور ان کے راشد جانشینوں کے زمانے میں بھی کوئی شخص جبر اور اکراہ سے
مسلمان نہیں بنایا گیا.اللهُ وَلَى الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمتِ إِلَى النُّورِ.وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَتُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّوْرِ إِلَى
الظُّلُمتِ أُولَئِكَ أَصْحَبُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ
الله وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا : اللہ جو سمیع علیم ہے اس کی پہچان کیا ہے.فرماتا ہے کہ وہ
مومنوں کا والی بن جاتا ہے.اب مومنوں کی پہچان بتاتا ہے کہ وہ ظلمات سے نکل کر نور کی طرف
آتے جاتے ہیں.ظلمت کیا ہے جس میں تمیز نہ رہے.روشنی کیا ہے جس میں تمیز ہو سکے.339
Page 348
معمولی روشنی سورج کی ہے پھر اس سے بڑھ کر ٹور طلب ہے جس سے انسان کے اندرونی
امراض معلوم ہوتے.پھر اس سے بڑھ کر نور فلاسفہ ہے کہ وہ خط و خال سے، بال سے ، آواز
سے، ناک سے، ہونٹ سے کسی کے اخلاق پر آگاہ ہو جاتے ہیں.پھر جن کو اس سے بھی بڑھ
کر انوار دیے جاویں وہ مومن ہیں چنانچہ فرمایا اِتَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللهِ پس
مومن ہونے کا نشان ہے کہ اس انسان کی قوت متمیزہ بڑھتی جاتی ہے اور وہ آہستہ آہستہ تاریکیوں
سے نکل کر انوار میں آتا جاتا ہے اور اپنی حالت میں دن بدن نمایاں تبدیلی پاتا ہے.ظلمتیں بھی کئی قسم کی ہوتی ہیں.ایک رسم کی ،مثلاً شادی آ گئی.اب رسم کہتی ہے کہ دس
ہزار روپیہ خرچ کرو.اب گھر میں تو اپنے روپے نہیں.پس ساہوکاروں کے پاس جاتا ہے.وہ
سُود مانگتا ہے.خدا فرماتا ہے جو سود دیتا یا لیتا ہے وہ خدا سے جنگ کرتا ہے.پھر اسی طرح
بڑھتے بڑھتے ایک گناہ سے کئی گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے.پھر عادت کی ظلمت ہے.یہ عادت بُری بلا ہے.جس چیز کی عادت پڑ جاوے وہ پیچھا نہیں
چھوڑتی.بعض کو قصہ سُنے کی دھت ہوتی ہے بعض کو ناول پڑھنے کی.بعض کو چائے پینے کی،
حقہ پینے کی، پان کھانے کی.پھر ظلمت سے شہوت ، حرص، غضب، سستی ، کاہلی.پس یہ بات
یا درکھو کہ جس تعلیم سے قوت ممیزہ بڑھے وہ بچی ہے.مِن الظُّلمت : 1 - والدین کی ظلمت 2 احباب کی ظلمت 3- کفر و شرک کی ظلمت
-4 - جہالت کی ظلمت 5 محبت کی ظلمت 6 عجز و کسل کی ظلمت 7 ظلم کی ظلمت
8.رسم و بدعت کی ظلمت.(ماخوذ از حقائق الفرقان)
حضرت خلیفہ اسیح الثانی فرماتے ہیں.الخلہ کے معنے ہیں اَلصَّدَاقَةُ دوستی اور محبت.اور تخلَّلَتِ الْقَلْبَ کے معنے ہیں دَخَلَتْ
خیاللہ وہ دوستی اور محبت جو دل کے اندر گھس کر اس کے سوراخوں میں داخل ہو جائے.( مجمع ابھار )
340
Page 349
الْخَلِيلُ مَنْ خُلَّتُه مَقْصُورَةٌ عَلَى حُبّ اللهِ تَعَالَى فَلَيْسَ فِيهَا لِغَيْرِهِ مُتَسَعُ وَلَا شِرَكَةٌ مِنْ فَحَاتٍ
الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ( مجمع البحار ) خلیل اسے کہتے ہیں جس کی محبت صرف اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ ہو
اور اس کے دل میں اس محبت کے سوا اور کسی کی محبت نہ ہو.حدیث میں آنحضرت تعلیم کا یہ قول
درج ہے کہ إِنِّي أَبْرَهُ مِنْ كُلّ ذِى خُلَّةٍ مِنْ خُلَّتِهِ لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيْلًا لَا أَخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ.یعنی
میں ہر شخص کی دوستی سے براءت کا اظہار کرتا ہوں اور صرف خدا تعالیٰ کی طرف تو جہ کرتا ہوں.اگر دنیا
میں میں کسی کو خلیل بنا تا تو ابوبکر کو بناتا.شَفَاعَةُ شَفَعَ سے نکلا ہے اور شَفَع کے معنے جُفت کے ہیں.يُقَالُ شَفَعَ الْعَدَدَ
وَشَفَعَ الصَّلوةَ صَيَّرَهَا شَفَعًا- یعنی شَفَعَ الْعَدَدَ کے معنے ہیں عدد کو جفت بنا یا اور شفَعَ
الصلوة کے معنے ہیں نماز کو جوڑ ا بنا دیا.اس آیت سے ظاہر ہے کہ اسلام نے صرف زکوۃ اور مال غنیمت کے اموال سے ہی
غرباء اور مساکین کی امداد کے لئے ایک فنڈ مقرر کرنے پر اکتفاء نہیں کیا بلکہ مسلمانوں کو عام
طور پر بھی غریبوں اور ناداروں کے لئے صدقہ وخیرات کرنے کی بار بار تا کید فرمائی ہے.اور
بتایا ہے کہ تمہارے ساتھ ترقیات کے جو وعدے کئے گئے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے کہیں یہ نہ سمجھ
لینا کہ ہمیں اب مزید قربانیوں کی ضرورت نہیں.قربانیاں
تمہیں قدم قدم پر کرنی پڑیں گی اور
قدم قدم پر تمہیں اپنے اموال خدا تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے پڑیں گے.لَا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ میں جس بیع کی طرف اشارہ ہے اس کا ذ کر دوسری جگہ
اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں فرمایا ہے.اِنَّ اللهَ اشْتَرى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَ
اَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ (تو به 111) یعنی اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ایک بیع کی ہے اور وہ یہ
کہ ان کے مالوں اور جانوں کو جنت دے کر خرید لیا ہے.پس فرما یا خدا تعالیٰ تم سے یہ بیع کرتا
ہے..مگر یہ بیع اسی دنیا میں ہوگی اُس دن نہیں ہوگی.وَلَا خُلةٌ میں بتایا کہ قیامت کے دن خدا تعالیٰ کے سوا سب خلیل جاتے رہیں گے.یہاں
341
Page 350
سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں تو دوسری جگہ آتا ہے.الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ
عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ (زخرف (68) یعنی متقیوں کے سوا تمام خلیل ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے.پھر جب متقیوں کی دوستی رہے گی تو لاخلہ کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ متقی چونکہ خدا
تعالیٰ کو ہی اپنا خلیل سمجھتے ہیں اس لئے ان کی دوستی خدا تعالی کی دوستی میں شامل ہوگی اس کا کوئی
علیحدہ وجود نہیں ہو گا جو وَلا خُلة کے منافی ہو.اصل مضمون جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو
توجہ دلائی ہے وہ یہ ہے کہ آج اگر خدا تعالیٰ کو خلیل بنانا ہے تو بنا لو ورنہ اس دن وہ خلیل نہیں بنے گا.اور آج جن کو تم اپنا خلیل بنا رہے ہو ان کی خُلت اور دوستی اس دن تمہارے کسی کام نہیں آئے گی
بلکہ تم ان کے دشمن بن جاؤ گے.صرف متقی ہی ایسے ہوں گے جو اپنے خلیل کے دشمن نہیں ہوں گے.کیونکہ مومن کا خلیل خدا تعالیٰ ہوتا ہے.پس وَلَا خُلہ سے مراد وہ خُلت ہے جو خدا تعالیٰ کے مقابلہ
میں کسی دوسرے سے کی جائے.وَلَا شَفَاعَةُ میں بتایا ساتھی بنالو.ورنہ وہاں تمہیں کوئی ساتھی نہیں ملے گا.دوسری جگہ
فرماتا ہے.وَانْذِرُ بِهِ الَّذِيْنَ يَخَافُونَ أَن تُحْشَرُ وا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا
شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ( انعام (52) یعنی تو اس کلام کے ذریعہ سے ان لوگوں کو جو اس بات
سے ڈرتے ہیں کہ انہیں ان کے رب کی طرف اکٹھا کر کے لے جایا جائے گا جب کہ اُس کے
سوانہ ان کا کوئی مددگار ہوگا اور نہ کوئی سفارشی اس لئے ڈرا کہ وہ تقویٰ اختیار کریں.اسی طرح ایک اور جگہ فرماتا ہے.وَذَكِّربة أن تُبسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا
مِنْ دُونِ اللهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِنْ تَعْدِلُ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذُ مِنْهَا (انعام (71) یعنی تو اس
کلام الہی کے ذریعہ سے نصحیت کر تا ایسا نہ ہو کہ کسی جان کو اس کے کماتے ہوئے کے سبب
سے اس طرح ہلاکت میں ڈال دیا جائے کہ خدا تعالیٰ کے سوا اس کا نہ کوئی مددگار ہو اور نہ شفیع.اور اگر وہ ہر ایک قسم کا بدلہ بھی دیں تو ان سے قبول نہیں کیا جائے گا.ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دنیا میں خدا تعالیٰ کو ولی اور شفیع بنانے والوں کو تو اس دن
342
Page 351
شفاعت کا حق پہنچے گا لیکن دوسروں کو نہیں.اور نہ ان کے حق میں شفاعت قبول ہوگی.خدا تعالیٰ کو
شفیع اس لئے قراردیا کہ اس کی اجازت کے بغیر شفاعت نہیں ہوسکتی.پس اصل شفیع وہی ہے.فرماتا ہے يَوْمَئِذٍ لَّا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا (طه 110) یعنی اس
دن شفاعت سوائے اس کے جس کے حق میں شفاعت کرنے کی اجازت رحمن خدا دیگا اور جس کے
حق میں بات کہنے کو وہ پسند کرے گا اور کسی کو نفع نہیں دے گی.اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہاں
شفاعت پالاذن ہو گی.خدا تعالی کے اذن کے بغیر شفاعت کا حق نہیں ہوگا.دوسری جگہ فرماتا
ہے.يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَطَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ
مُشْفِقُونَ (الانبیاء (29) یعنی خدا تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے جو انہیں آئندہ پیش آنے والا ہے اور جو
وہ پیچھے چھوڑ آئے ہیں اور وہ سوائے اس کے جس کے لئے خدا نے یہ بات پسند کی ہو کسی کے لئے
شفاعت نہیں کرتے اور وہ اس کے خوف سے لرزتے رہتے ہیں.پھر اس آیت سے اگلی آیت میں
فرماتا ہے مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ( البقرة2565) یعنی کون ہے جو اس کی اجازت
کے بغیر اس کے حضور کسی کی سفارش کرے.بیشک حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن آنحضرت معالم اور انبیاء سابقین
کے علاوہ آنحضرت علیم کے بعض امتی بھی شفاعت کریں گے.لیکن ان حدیثوں کے
بارے میں میری تشریح یہ ہے کہ امت محمدیہ میں ایسے افراد کی شفاعت صرف ظنی ہوگی اصل شفیع
آنحضرت علیم ہی ہوں گے.وہ محمد رسول اللہ صل علیم سے سفارش کریں گے اور آپ اللہ تعالیٰ
سے.بانی سلسلہ احمدیہ نے بھی اسی عقیدہ کی توضیح فرمائی ہے.آپ اپنی کتاب کشتی نوح میں
فرماتے ہیں.نوع انسان کے لئے رُوئے زمین پر اب کوئی رسول اور شفیع نہیں مگر محمد مصطفے صلی اللہ
علیہ وسلم.سو تم کوشش کرو کہ سچی محبت اس جاہ و جلال کے نبی کے ساتھ رکھو.اور اُس کے غیر
کو اُس پر کسی نوع کی بڑائی مت دو تا آسمان پر تم نجات یافتہ لکھے جاؤ.“
343
Page 352
بہر حال جب تک کوئی انسان اللہ اور اس کے رسول سے واصل نہ ہو جائے اور ان کو
اپنا جوڑا نہ بنالے اس وقت تک اسے کسی قسم کی شفاعت میسر نہیں آئے گی.وَالْكَفِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ میں بتایا کہ ظلم نہیں بلکہ ظلم کفار نے خود اپنی جانوں پر کیا ہے.اللهُ لا إلهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي
السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ
مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا مَا
شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوتِ وَ الْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَ هُوَ
الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ (البقرة 256)
* الحى : کامل حیات والا.اللہ تعالیٰ کے لئے جب اٹھی آتا ہے تو الف لام کمال کے
معنے دیتا ہے اور اس کے معنے یہ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالی حیات کا ملہ رکھتا ہے یعنی ایسی حیات جو
اپنے قیام میں کسی اور کی محتاج نہیں.اسے کسی اور نے زندگی نہیں بخشی بلکہ اس کی ذات ازلی
اور ابدی طور پر زندہ ہے.الْقَيُّومُ قَامَ سے نکلا ہے جس کے معنے کھڑے ہونے کے ہیں.اسی سے قیم نکلا
ہے جس کے معنے نگران اور متولی کے ہیں اور قیم مُسْتَقِيمٌ کو بھی کہتے ہیں.آمْرٌ قَيَّمُ ایسا
امر جس میں کوئی کمی نہ ہو بلکہ درست اور ٹھیک ہو.الْقَيُّومُ اور الْقَيَّامُ کے معنے ہیں جو اپنی ذات میں قائم ہے اور اس کی کوئی ابتدا نہیں
(اقرب) الْقَيُّومُ صرف اسی کو نہیں کہتے جو اپنی ذات میں قائم ہو بلکہ اس کے معنوں میں
دوسرے کو قائم رکھنا اور اس کی حفاظت کرنا بھی شامل ہے.اور اللہ تعالیٰ القَيُّومُ ہے.نہ صرف اس لئے کہ وہ خود قائم ہے بلکہ اس لئے بھی کہ دوسری
سب اشیاء اس کی پیدا کردہ طاقتوں سے قائم رہتی ہیں.الْقَيُّومُ کی صفت اجرام فلکی میں
کشش ثقل کے وجود اور خور دبینی ذرات کے ایک دوسرے اتصال اور ایک دوسرے سے
344
Page 353
ادغام اور ایک دوسرے کے گردگھومنے وغیرہ افعال پر لطیف رنگ میں اشارہ کرتی ہے.سنہ سے مراد وہ اونگھ ہے جو نیند کے غلبہ کی وجہ سے آنے لگے.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہ اسے اونگھ آتی ہے اور نہ نیند.حالانکہ جب اونگھ کی نفی کر دی گئی تھی تو
نیند کی خود ہی نفی ہو جاتی ہے.پھر نیند کی نفی کی کیا ضرورت تھی؟ سو یا درکھنا چاہئے کہ اس میں
ایک حکمت ہے.اور وہ یہ کہ سنہ اس کو کہتے ہیں کہ جب سخت نیند کی وجہ سے انسان کی
آنکھیں بند ہو جائیں.چنانچہ جب انسان کو بہت زیادہ نیند آئی ہوئی ہو اس وقت اونگھ آتی
ہے.اور جب تک نیند کا غلبہ نہ ہو اونگھ نہیں آتی.تو فرمایا کہ خدا تعالیٰ کو کبھی اونگھ نہیں آتی کہ
کام کرنے کی وجہ سے وہ تھک گیا ہو.اور اس پر نیند کا ایسا غلبہ ہو کہ اس کی آنکھیں بند ہوگئی
ہوں اور نہ اسے معمولی نیند آتی ہے.غرض ترتیب بیان کے لحاظ سے سنة کا ہی پہلے ذکر آنا
ضروری تھا.اور نوم کا بعد میں.له مَا فِي السَّمَوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
تمہارا آقا ایسا ہے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب کچھ اُسی کا ہے.ایسی
صورت میں تم اس کے مقابلہ میں کسی اور کو اپنا آقا کس طرح بنا سکتے ہو.پھر بعض لوگ کہتے
ہیں کہ ہم خدا تعالیٰ کے سوا اور کسی کی عبادت تو نہیں کرتے ہاں دوسروں کو نیا زمیں دیتے اور ان
سے مرادیں مانگتے ہیں.کیونکہ وہ خدا تعالیٰ کے مقرب ہیں.اور وہ خدا تعالیٰ کے حضور ہماری
شفاعت کریں گے.خدا تعالی فرماتا ہے مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ.ہمارے حکم
کے بغیر تو کوئی شفاعت ہی نہیں کر سکتا.پس تمہاری یہ امید بھی غلط ہے.حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن آنحضرت علی ایم کو اذن ہو گا تب آپ
سفارش کریں گے.پھر کیسانادان ہے وہ شخص جو سمجھتا ہے کہ فلاں میری سفارش کر دے گا.يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ کے دو معنے ہیں.ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی
جانتا ہے جو آگے ہونا ہے اور اسے بھی جانتا ہے جولوگ پیچھے کر چکے ہیں.345
Page 354
دوسرے معنے یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کاموں کو بھی جانتا ہے جو وہ کر رہے ہیں اور ان کاموں کو
بھی جانتا ہے جو انہیں کرنے چاہیے تھے.لیکن انہوں نے ترک کر دئیے.* لَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا مَا شَاءَء میں اس امر کی طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے
-
کہ اللہ تعالیٰ کے قرب کی راہیں اتنی غیر محدود ہیں کہ انہیں گلی طور پر طے کرنے کا کوئی انسان
خیال بھی نہیں کر سکتا.جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے قرب میں بڑھتا ہے اور وہ اپنے مقام کے
مطابق اس کے انوار و برکات کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس پر
اپنی دوسری تجلی ظاہر کرتا ہے اور جب وہ دوسری تجلی کی بھی برداشت کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ
دیکھتا ہے کہ اب یہ تیسری تجلی کے قابل ہو گیا ہے تو اس پر اپنی تیسری تجلی ظاہر کرتا ہے اور وہ
خدا تعالیٰ کے قرب میں بڑھتا چلا جاتا ہے.الكرسى : کیسی سے نکلا ہے جس کے معنے متفرق اجزاء کے اکٹھا ہونے کے
ہوتے ہیں.کہتے ہیں گوشت بنا.میں نے عمارت بنائی یعنی اینٹوں پر اینٹیں رکھیں.اور
کرسی علم کو بھی کہتے ہیں اور حکومت کو بھی (مفردات ) اس لفظ کی اصل سے معلوم ہوتا ہے کہ
اصل میں اس کے معنے جمع کرنے اور اکٹھا کرنے کے ہیں.اور چونکہ علم بھی پراگندہ اجزاء کو
جمع کر لیتی ہے اس لئے اسے بھی کرسی کہتے ہیں.* وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوتِ وَالْأَرْضَ اللہ تعالیٰ کا علم آسمان اور زمین کو گھیرے ہوئے
ہے.یعنی اسے ہر چیز کا انتہائی علم ہے.اور کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کے علم سے باہر ہو.انسانی علم بالکل محدود ہوتا ہے.وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ میں سائنس کے اس عظیم الشان نکتہ کی طرف بھی
اشارہ کیا گیا ہے کہ کائنات عالم کی لمبائی کا اندازہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا.علی میں اس کی رفعت اور بلندی کی طرف اور عظیم میں اس کی طاقتوں کی وسعت کی
طرف اشارہ کیا ہے.یہ وہ خدا ہے جو اسلام پیش کرتا ہے.346
Page 355
* الْعُرْوَةُ مِنَ الدَّلْوِ وَالْكُوزِ الْمِقْبَضُ الَى أَذْنُهُما.یعنی عروہ ڈول یا لوٹے کے دستہ کو
کہتے ہیں جس سے اسے پکڑا جاتا ہے.اسی طرح عُروہ کے معنے مایو تقی بہ کے بھی ہیں.یعنی
ایسی چیز جس پر اعتبار کیا جائے.گویا ہر ایسی چیز جس پر سہارا لیا جائے یا جس پر اعتماد کیا جاسکے
وہ مروہ کہلاتی ہے.اسی طرح عروہ اس چیز کو بھی کہتے ہیں جو کبھی ضائع نہ ہونے والی ہو.چنانچہ محر وہ اس گھاس کو کہتے ہیں جو ہمیشہ ہر ار ہے اور غمروہ کے معنے النَّفِيسُ مِنَ الْمَالِ کے
بھی ہیں.یعنی اچھا اور بہترین مال.یہ عجیب بات ہے کہ اسلام پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ وہ جبر سے دین پھیلانے کی
تعلیم دیتا ہے حالانکہ اسلام اگر ایک طرف جہاد کے لئے مسلمانوں کو تیار کرتا ہے جیسا کہ اس
سورۃ میں وہ فرما چکا ہے کہ قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقْتِلُونَكُمْ (البقرة 191) یعنی تم
اللہ تعالی کی راہ میں ان لوگوں سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں.تو دوسری طرف وہ یہ
بھی فرماتا ہے کہ لا اخر الا فی الدین.یعنی جنگ کا جو حکم تمہیں دیا گیا ہے اس سے یہ نہیں
سمجھنا چاہیے کہ لوگوں کو مسلمان بنانے کے لئے جبر کرنا جائز ہو گیا ہے.بلکہ جنگ کا یہ حکم محض
دشمن کے شر سے بچنے اور اس کے مفاسد کو دور کرنے کے لئے دیا گیا ہے.اگر اسلام میں جبر
جائز ہوتا تو یہ کس طرح ہو سکتا تھا کہ قرآن کریم ایک طرف تو مسلمانوں کولڑائی کا حکم دیتا اور
دوسری طرف اسی سورۃ میں یہ فرما دیتا کہ دین کے لئے جبر نہ کرو.کیا اس کا واضح الفاظ میں یہ
مطلب نہیں کہ اسلام دین کے معاملہ میں دوسروں پر جبر کرنا کسی صورت میں بھی جائز قرار نہیں
دیتا.پس یہ آیت دین کے معاملہ میں ہر قسم کے جبر کو نہ صرف ناجائز قرار دیتی ہے بلکہ جس
مقام پر یہ آیت واقع ہے اس سے بھی صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام جبر کے بالکل خلاف ہے.قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَي.یہ جملہ مستأنفہ ہے یعنی اس سے پہلے ایک جملہ مقدر ہے
جس کا یہ جواب دیا گیا ہے.چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ دین کے لئے جبر جائز نہیں.اس لئے سوال پیدا ہوتا تھا کہ جب دین ایک اعلیٰ درجہ کی چیز ہے تو کیوں اس کے لئے لوگوں
347
Page 356
پر جبر نہ کیا جائے.اور انہیں بزور اس نعمت سے متمتع نہ کیا جائے.اللہ تعالیٰ اس سوال کے جواب میں فرماتا ہے جب گمراہی اور ہدایت ظاہر ہوگئی ہے تو اب
جبر کی ضرورت نہیں.صرف ہدایت کا پیش کر دینا تمہارا کام ہے.کیونکہ جو حق بات تھی وہ گمراہی
اور ضلالت کے بالمقابل پورے طور پر ظاہر ہوگئی ہے.غرض اس آیت میں خدا تعالیٰ نے وجہ بیان فرمائی ہے کہ کیوں اسلام کو جبر کی ضرورت
نہیں.فرماتا ہے.جبر اس وقت ہوتا ہے جب کوئی بات دلیل سے ثابت نہ ہو سکے.یا جس
کو سمجھایا جائے وہ سمجھنے کے قابل نہ ہو.مثلاً ایک بچہ کی عقل چونکہ کمزور ہوتی ہے.اس لئے
بسا اوقات اس کی مرضی کے خلاف اور جبر کرنے والے کی مرضی کے موافق کام کرنے پر مجبور کیا
جاتا ہے.لیکن اس بچہ میں جب عقل آجاتی ہے تو پھر وہ اپنے آپ ہی سمجھ جاتا ہے اور اپنے نفع
اور نقصان کو سوچ سکتا ہے.اس حالت میں اس پر کوئی جبر نہیں کرتا.اسلام کے متعلق
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس میں ہر قسم کے دلائل کو کھول کر بیان کر دیا گیا ہے.اس لئے اسے
منوانے کے لئے کسی پر جبر کرنے کی ضرورت نہیں.اسلام صرف ان لوگوں سے دینی جنگ کرنے کا حکم دیتا ہے جو دین کے نام سے مسلمانوں
سے جنگ کریں اور مسلمانوں کو جبراً اسلام سے پھیر نا چاہیں.اور ان کے متعلق بھی یہ حکم دیتا
ہے کہ زیادتی نہ کرو بلکہ اگر وہ باز آجائیں تو تم بھی اس قسم کی لڑائی کو چھوڑ دو.تو پھر یہ کیونکر کہا جا
سکتا ہے کہ اسلام کا حکم ہے کہ غیر مذاہب والوں سے اپنے مذہب کی اشاعت کے لئے
جنگ کرو.اللہ تعالیٰ تو مختلف مذہبوں کے مٹانے کے لئے نہیں بلکہ مختلف مذاہب کی
حفاظت کے لئے جنگ کرنے کا حکم دیتا ہے.جیسا کہ وہ فرماتا ہے.أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقْتَلُونَ
بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرُ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍ إِلَّا أَنْ يَقُو
لُوا رَبُّنَا اللهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوتُ وَمَسْجِدُ
يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزُ (الحج 40-41) یعنی
348
Page 357
ان لوگوں کو جن سے جنگ کی جاتی ہے جنگ کی اس وجہ سے اجازت دی جاتی ہے کہ ان پر ظلم
کیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر قادر ہے.یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے بلا قصور نکا
لے گئے ہیں.ان کا کوئی قصور نہ تھا سوائے اس کے کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ ہمارا رب ہے.اور
اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کے ذریعہ سے بعض کا ہاتھ نہ روکتا تو مسیحیوں کے معبد اور راہبوں کے
خلوت خانے اور یہود کی عبادتگا ہیں اور مسجدیں جن میں اللہ تعالیٰ کا نام کثرت سے لیا جاتا ہے
گرا دی جاتیں.اور یقینا اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا جو اس کے دین کی تائید کرے گا اور اللہ
تعالیٰ بہت طاقتور اور غالب ہے.یہ آیات کس قدر کھلے الفاظ میں بتاتی ہیں کہ مذہبی جنگیں تبھی
جائز ہیں جبکہ کوئی قوم ربنا اللہ کہنے سے روکے.یعنی دین میں دخل دے اور چاہے کہ دوسری
اقوام کے معاہد گرائے جائیں اور ان سے ان کا مذہب چھڑوایا جائے.یا ان کو قتل کیا
جائے.ایسی صورت میں اسلام اس قوم سے جنگ کی اجازت دیتا ہے.کیونکہ اسلام دنیا میں
بطور شاہد اور محافظ کے آیا ہے نہ کہ بطور جابر اور ظالم کے.فَمَن يَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ کے متعلق یہ امر یا درکھنا چاہئے کہ کفر کے معنے صرف انکار کرنے
کے ہوتے ہیں خواہ وہ کسی چیز کا انکار ہو.قرآن کریم میں یہ لفظ اچھے معنوں میں بھی استعمال ہوا
ہے اور برے معنوں میں بھی.اس جگہ یہ لفظ اچھے معنوں میں استعمال ہوا ہے.اور اللہ تعالیٰ
فرماتا ہے کہ جو لوگ شیطانوں اور شیطانی لوگوں کی باتیں ماننے سے قطعی طور پر انکار کر دیتے ہیں
اور اللہ تعالیٰ پر سچے دل سے ایمان لے آتے ہیں وہ ایک مضبوط چٹان پر قائم ہو جاتے ہیں.لیکن اس کے مقابلہ میں قرآن کریم میں يَكْفُرُونَ بِالله (نساء 151) بھی آتا ہے کہ کچھ
لوگ اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں.پس جہاں تک اس لفظ کے ظاہر کا تعلق ہے یہ نہ بُرا ہے نہ
اچھا ہے.اصل معنے تو اس کے ڈھانپ دینے کے ہوتے ہیں.بدی کا ڈھانپنا بھی کفر
کہلائے گا اور نیکی کاڈھانپنا بھی کفر کہلائے گا.بدی کا چھپانا بھی کفر کہلائے گا اور نیکی کا چھپانا
بھی کفر کہلائے گا.لیکن چونکہ کثرت سے قرآن کریم میں یہ لفظ نیکی کے انکار کے متعلق استعمال
349
Page 358
ہوا ہے اس لئے جب کسی قرینہ کے بغیر یہ لفظ استعمال ہوتو اس کے معنے برے ہی کئے جاتے
ہیں.جس طرح مومن کے معنے بھی ایسے ہی ہیں لیکن وہ زیادہ تر نیکی کے معنوں میں استعمال ہوتا
ہے.اس لئے جب مومن کا لفظ بغیر کسی قرینہ کے استعمال ہو تو اس کے معنے ہمیشہ نیک کے ہی
کئے جائیں گے.حالانکہ قرآن کریم میں مومن کا لفظ بھی برے معنوں میں استعمال ہوا ہے جیسا
کہ فرماتا ہے.يُؤْمِنُونَ بِالجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ (نساء 25) وہ بے فائدہ باتوں اور حد سے.بڑھنے والوں پر ایمان رکھتے ہیں.اس جگہ فَمَن يَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ میں طاغوت کا کفر کرنے
سے اس کی ذات کا انکار مراد نہیں بلکہ یہ مراد ہے کہ اس کی بات نہ مانے.اس کے مقابلہ
میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کا لفظ رکھا ہے جس کے معنے خدا تعالیٰ کی بات ماننے کے ہیں.اور
فرمایا ہے کہ جو شخص طاغوت کا انکار کرتا ہے اور اللہ تعالی پر ایمان لاتا ہے وہ ایسے مضبوط کڑے
کو پکڑ لیتا ہے جو کبھی ٹوٹتا ہی نہیں.عُروہ کے معنے دستہ کے بھی ہوتے ہیں جس پر اعتبار کیا جائے اور عُروہ کے معنے ایسی چیز کو
بھی کہتے ہیں جس کی طرف انسان ضرورت کے وقت رجوع کرے.اور غمروہ اس چیز کو بھی کہتے
ہیں جو ہمیشہ قائم رہے اور
کبھی ضائع نہ ہو.اور غروہ بہترین مال کو بھی کہتے ہیں.(1) اگر غروہ کے معنے دستہ کے لئے جائیں تو اس آیت کا یہ مطلب ہوگا کہ دین کو خدا
تعالیٰ نے ایک ایسی لطیف چیز قرار دیا ہے جو کسی برتن میں پڑی ہوئی ہو اور محفوظ ہو اور انسان
نے اس برتن کا دستہ پکڑ کر اسے اپنے قبضہ میں کرلیا ہو.(2) پھر غروہ کہہ کر اس طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ دین ایک ایسی چیز ہے جس کا
انسان سہارا لے لیتا ہے تا کہ اسے گرنے کا ڈر نہ رہے.جیسے سیڑھیوں پر چڑھنے کے لئے
انسان کو رشہ کی ضرورت پڑتی ہے اور وہ اسے پکڑ لیتا ہے.اسی طرح دین بھی اس رشتہ کی طرح
ایک سہارا ہے.اسے مضبوط پکڑ لینے سے گرنے کا ڈر نہیں رہتا.(3) غروہ کہہ کر یہ بھی بتایا کہ اگر انسان اسے مضبوطی سے پکڑلے تو وہ ہر مصیبت کے وقت
اس کے کام آتا ہے.350
Page 359
الله ولى الَّذِينَ آمَنُوا
فرماتا ہے.اللہ مومنوں کا دوست اور مدد گار رہے.اور وہ ایمان لانے والوں کو
اندھیروں سے روشنی کی طرف لاتا ہے.عربی زبان کے محاورہ میں کامیابی کی طرف لے جانے
کو ظلمت سے نور کی طرف لے جانے سے تعبیر کیا جاتا ہے.خواہ وہ کامیابی جسمانی ہو یا
روحانی.پس اس سے مراد مومنوں کی جماعت کو ہر قسم کی روحانی اور جسمانی کامیابیوں کی طرف
لے جانا اور انہیں ہر قسم کی ناکامیوں اور تکالیف سے نجات دلانا ہے.وَالَّذِينَ كَفَرُوا اَوْلِيَتُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى
الظُّلُمتِ.* یہاں طاغوت سے مراد وہ لوگ ہیں جو شیطان کے قائم مقام ہوتے ہیں.وہ لوگوں کواس
تھوڑی بہت ہدایت سے بھی جس پر وہ قائم ہوتے ہیں دُور پھینک دیتے ہیں.یہ مت خیال
کرو کہ کفار میں نور کہاں سے آیا.رسول کریم علیم نے جب دعوی نہیں کیا تھا اس وقت
ابو جہل ایسا برا نہیں تھا جیسا کہ اُس وقت تھا جب کہ وہ مارا گیا.بات یہ ہے کہ صداقت کے
انکار سے انسان کے قلب پر زنگ لگ جاتا ہے اور ہوتے ہوتے وہ تھوڑا بہت نور جو اس کے
دل میں ہوتا ہے وہ بھی جاتا رہتا ہے.يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمتِ إِلَى النُّورِ میں خدا تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ جولوگ
اللہ تعالیٰ کے ہو جاتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ بحیثیت قوم ترقی کی طرف لے جاتا ہے.مگر چونکہ دنیا
میں انسان کو قدم قدم پر مشکلات پیش آتی رہتی ہیں جن کو دیکھ کر بعض لوگوں کو یہ دھوکا لگ جاتا
ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی کامیابی کا وعدہ کیا ہے تو پھر انہیں مشکلات کیوں پیش آتی
ہیں.اس لئے یا درکھنا چاہئے کہ یہ وعدے قومی طور پر کئے گئے ہیں نہ کہ انفرادی طور پر.پس
انفرادی تکالیف اور مشکلات کو اس وعدہ کے خلاف نہیں سمجھنا چاہئے.اگر کوئی شخص مارا
جاتا ہے لیکن اس کے مرنے سے قوم کو فائدہ پہنچتا ہے تو وہ مرتا نہیں بلکہ زندہ ہوتا ہے.ورنہ
351
Page 360
ظاہری تکالیف کو دیکھا جائے تو حضرت امام حسین بھی شہید کر دئیے گئے تھے.مگر وہ نا کام نہیں
ہوئے بلکہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے اور جس اصول کی خاطر انہوں نے قربانی پیش کی تھی
وہ اصول آج بھی قائم ہے اور قیامت تک قائم رہے گا.(ماخوذ از تفسیر کبیر از حضرت خلیفة المسیح الثانی)
حضرت خلیفتہ اسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے آیت الکرسی کی تلاوت
ایدہ
کے بعد فرمایا:
اس آیت کا ترجمہ ہے کہ اللہ، اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں.ہمیشہ زندہ رہنے والا اور
قائم بالذات ہے.اسے نہ تو اونگھ پکڑتی ہے اور نہ نیند.اسی کے لئے ہے جو آسمانوں میں ہے
اور جو زمین ہے.کون ہے جو اس کے حضور شفاعت کرے مگر اس کے اذن کے ساتھ.وہ
جانتا ہے جو اس کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے.اور وہ اس کے علم کا کچھ بھی احاطہ نہیں
کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے.اسی کی بادشاہت آسمانوں اور زمین پر ممتد ہے.اور ان دونوں کی
حفاظت اسے تھکاتی نہیں.اور وہ بہت بلندشان اور بڑی عظمت والا ہے.یه آیت..آیت الکرسی کہلاتی ہے.ایک حدیث میں آتا ہے جو حضرت ابوہریرہ رضی اللہ
تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ ہر چیز کا ایک چوٹی کا حصہ ہوتا ہے اور
قرآن کریم کی چوٹی کا حصہ سورۃ البقرہ ہے اور اس میں ایک ایسی آیت ہے جو قرآن کریم کی
سب آیات کی سردار ہے.اور وہ آیت الکرسی ہے.( سنن الترمذی کتاب فضائل القرآن باب ما جاء في فضل سورة البقرة وآية الكرسی حدیث نمبر 2878)
اسی طرح یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص سورۃ البقرۃ کی دس
آیات پڑھ کر سوئے صبح تک اس کے گھر میں شیطان نہیں آتا.ان آیات میں سے ایک آیت،
آیت الکرسی ہے.( سنن الدارمی کتاب فضائل القرآن باب فضل اول سورة البقرة وآية الكرسی حدیث نمبر 3383)
352
Page 361
آنحضرت ﷺ کا یہ فرما نا صرف اسی حد تک نہیں ہے کہ پڑھ لی اور سو گئے.اس کا مطلب یہ
ہے کہ اس آیت کو اور ان آیات کو غور سے پڑھا جائے.ان پر غور کیا جائے.ان کے معانی پر
غور کیا جائے.پھر انسان اپنا جائزہ لے اور دیکھے کہ کس حد تک ان پر عمل کرتا ہے، کس حد
تک اس میں پاک تبدیلیاں ہیں اور جائزہ لینے کے بعد جو بھی صورت حال سامنے آئے ، یہ عہد
کرے کہ آئندہ سے یہ پاک تبدیلیاں میں اپنے اندر پیدا کروں گا.پھر یہ چیز ہے جو شیطان
سے دُور کرتی ہے.جن دس آیتوں کا ذکر کیا گیا ہے ان میں سے چار آیات جو ہیں وہ سورۃ البقرہ کی پہلی چار
آیات ہیں.جن میں ایک مومن کی پاکیزہ عملی زندگی کا نقشہ کھینچا گیا ہے اور جیسا کہ میں نے کہا
ایک آیت ، آیت الکرسی ہے اور اس کے ساتھ کی دو آیات ہیں جن میں صفات باری کا نقشہ کھینچا
گیا ہے.پھر سورۃ البقرہ کی آخری تین آیات ہیں جن میں سے آخری آیت کی وضاحت میں
نے گزشتہ جمعہ میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تفسیر کی روشنی میں کی تھی.گو اس وقت
مضمون تو آیت الکرسی کا ہی بیان ہوگا لیکن اس سے پہلے سورۃ بقرہ کی پہلی چار آیات میں سے
الم ذلِكَ الْكِتَبُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِين کے بارہ میں حضرت مسیح موعود
علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تفسیر بیان فرمائی ہے اس کا ایک اقتباس میں پڑھوں گا جو اللہ تعالیٰ
کے پاک کلام قرآن کریم کی وسعتوں کی طرف ، اس کو سمجھنے کی طرف ہماری رہنمائی
کرتا ہے.اور اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے قرآن کریم کو سمجھنا آسان بھی ہے اور انسان صحیح
طرح سمجھ سکتا ہے.حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ : ”جب تک کسی کتاب کے علل
اربعہ کامل نہ ہوں.وہ کامل کتاب نہیں کہلا سکتی.علل اربعہ کا مطلب ہے کہ چار بنیادی
خصوصیات.اگر یہ چار بنیادی صفات کامل ہوں تب ہی وہ کتاب کامل کہلا سکتی ہے.آپ فرماتے ہیں : اس لئے خدا تعالیٰ نے ان آیات میں قرآن شریف کے علل اربعہ کا
353
Page 362
ذکر فرما دیا ہے اور وہ چار ہیں.(1) علت فاعلی ،(2) علت مادی ،(3) علت صوری
اور (4) علت غائی“.فرمایا کہ ہر چہار کامل درجہ پر ہیں.پس الھ علت فاعلی کے کمال کی
طرف اشارہ کرتا ہے جس کے معنی ہیں کہ انا اللہ اعلم.یعنی کہ میں جو خدائے عالم الغیب ہوں
میں نے اس کتاب کو اتارا ہے.پس چونکہ خدا اس کتاب کی علت فاعلی ہے اس لئے اس
کتاب کا فاعل ہر ایک فاعل سے زبر دست اور کامل ہے.“
(حقیقۃ الوحی روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 136 - حاشیہ)
پس قرآن کریم کے کامل کتاب ہونے کی سند اور غیروں کو چیلنج ابتدا میں ہی ان تین حروف
میں خدا تعالیٰ نے دے دیا.اس پر ایمان لانے والوں کو کسی بھی قسم کا خوف اور احساس کمتری
نہیں ہونا چاہئے.کسی قسم کے خوف اور احساس کمتری میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ
یہ اس خدا کا کلام ہے جس کے کاموں کی گنہ تک بھی انسان نہیں پہنچ سکتا اور کھلا چیلنج ہے کہ
قرآن کریم کی ایک سورۃ جیسی سورۃ لے کے آؤ اور اپنے ساتھ تمام مددگاروں کو ملا لو تو بھی تمام
مددگاروں سمیت نہیں لا سکتے.بہر حال اس بات کی تفصیل میں تو میں نہیں جا رہا.مختصر یہ کہ
قرآن کریم کامل کتاب اس لئے ہے کہ اس کو اتارنے والا کامل اور سب قدرتوں اور طاقتوں کا
مالک اور عالم الغیب خدا ہے.دوسری بات یہ فرمائی کہ : "ملت مادی کی طرف اشارہ کرتا ہے یہ فقرہ کہ ذلِك الكتب
یعنی یہ وہ کتاب ہے جس نے خدا کے علم سے خلعت وجود پہنا ہے اور اس میں کچھ شک نہیں کہ
خدا تعالی کا علم تمام علوم سے کامل تر ہے.بلکہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ میرے علم کی وسعتوں کی
انتہا نہیں ہے.انسان اس کا احاطہ کر ہی نہیں سکتا.اللہ تعالیٰ نے اپنے کامل اور وسیع علم سے کچھ
حصہ اپنے پیارے نبی
ﷺ کے ذریعہ اس کتاب میں ہمیں بتایا.اور پھر تیسری چیز حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ، فرمایا: ”اور علت
صوری کی طرف اشارہ کرتا ہے یہ فقرہ لاریب فیہ.یعنی یہ کتاب ہر ایک غلطی اور شک وشبہ
سے پاک ہے.اور اس میں کیا شک ہے کہ جو کتاب خدا تعالیٰ کے علم سے نکلی ہے وہ اپنی
354
Page 363
صحت اور ہر ایک عیب سے مبرا ہونے میں بے مثل و مانند ہے اور لا ریب ہونے میں اکمل
اور اتم ہے.“
پھر آپ نے فرمایا اور علت غائی یعنی اس کی جو بنیادی وجہ ہے علت غائی کے کمال کی
طرف اشارہ کرتا ہے یہ فقرہ کہ هُدًى لِّلْمُتَّقین.یعنی یہ کتاب ہدایت کامل متقین کے لئے ہے
اور جہاں تک انسانی سرشت کے لئے زیادہ سے زیادہ ہدایت ہو سکے وہ اس کتاب کے ذریعہ
سے ہوتی ہے.“
( حقیقۃ الوحی روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 137-136 - حاشیہ)
ہدایت اور عرفان الہی کے بھی مدارج ہیں.پس قرآن کریم کی تعلیم پر غور اور عمل، ہدایت
اور عرفان الہی کی نئی سے نئی راہیں کھولتا ہے.یہ چار باتیں قرآن پڑھتے وقت اگر ہمارے
سامنے ہوں اور ان پر ایمان اور یقین ہو تو قرآن کریم کو سمجھنے اور اس کا صحیح ادراک حاصل کرنے
کی طرف راہنمائی ملتی ہے.اب میں آیت الکرسی کی کچھ وضاحت کروں گا.اس آیت میں بھی خدا تعالیٰ کے
جامع الصفات اور وسیع تر ہونے کا مضمون ہے.اس آیت کی ابتدا ہی اللہ تعالیٰ کے نام سے
ہوتی ہے.اللہ کیا ہے؟ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ :
اللہ جو خدائے تعالیٰ کا ذاتی اسم ہے اور جو تمام جمیع صفات کا مستجمع ہے.“ فرمایا ” کہتے
ہیں کہ اسم اعظم یہی ہے اور اس میں بڑی بڑی برکات ہیں لیکن جس کو وہ اللہ یاد ہی نہ ہو وہ اس
سے کیا فائدہ اٹھائے گا.“
( ملفوظات جلد اول صفحہ 63 جدید ایڈیشن)
پس جب ایک انسان مومن ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کو سب طاقتوں کا
سر چشمہ یقین کرنا چاہئے اور اسے تمام صفات کا اس حد تک احاطہ کئے ہوئے سمجھنے پر ایمان ہونا
چاہئے، جہاں تک انسان کے فہم و ادراک کی رسائی نہیں ہوسکتی.جو بے کنار ہے اور جب یہ
ایمان ہوگا تو تبھی ہر موقع پر خدا تعالیٰ یا در ہے گا.بہت سی برائیوں میں انسان اس لئے مبتلا ہو
355
Page 364
جاتا ہے یا اللہ تعالیٰ کے احکامات کے بجا لانے میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی میں
سستی اس لئے ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت انسان کو یاد نہیں رہتا.انسان بھول جاتا ہے
کہ خدا تعالیٰ کی ہر لمحہ اور ہر آن مجھ پر نظر ہے.حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ : ” خدا نے مجھے مخاطب
کر کے فرمایا کہ میں اپنی جماعت کو اطلاع دوں کہ جولوگ ایمان لائے ایسا ایمان جو اس کے
ساتھ دنیا کی ملونی نہیں اور وہ ایمان نفاق یا بزدلی سے آلودہ نہیں اور وہ ایمان اطاعت کے کسی
درجہ سے محروم نہیں، ایسے لوگ خدا کے پسندیدہ لوگ ہیں.اور خدا فرماتا ہے کہ وہی ہیں جن کا
قدم صدق کا قدم ہے.“
( رساله الوصیت روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 309)
تو یہ کم از کم کوشش ہے جو ہمیں اپنے اللہ پر ایمان لانے اور پھر ترقی کی طرف قدم
بڑھانے کے لئے کرنی چاہئے جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے.اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے اس طرح شروع کیا کہ اللهُ لا إلهَ إِلَّا هُو.یعنی صرف اللہ کو
دیکھو کہ وہی تمہارا معبود ہے اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے.یہ واضح فرما دیا کہ اللہ ہی
تمام صفات کا جامع اور تمام قدرتوں کا مالک ہے اور اس ناطے وہی اس بات کا حقدار ہے کہ
اس کی عبادت کی جائے اور تمام جھوٹے خداؤں سے کنارہ کشی کرتے ہوئے ، بچتے ہوئے ،
صرف اسی واحد خدا کے سامنے جھکا جائے.فرمایا کہ اس واحد خدا کے سامنے جھکو گے تو پھر ہی دنیا و آخرت کے انعامات سے فیض پا
سکتے ہو.دنیا میں ہر چیز کا بدل مل سکتا ہے لیکن خدا تعالیٰ کا کوئی بدل نہیں ہے.جب اس کا بدل
نہیں ہے تو پھر بیوقوفی ہے کہ اسے چھوڑ کر کہیں اور جایا جائے.یا عارضی طور پر ہی اپنی ترجیحات
کو بدل دیا جائے.ایک دہر یہ تو یہ کہہ سکتا ہے کہ میں کیونکہ خدا کو نہیں مانتا اس لئے میں کیوں
اس کے در پر حاضر ہو جاؤں.لیکن ایک مسلمان جب یہ دعویٰ کرتا ہے کہ لا إلهَ إِلَّا اللہ اور پھر
دنیاوی ذریعوں کو خدا سے زیادہ اہمیت دیتا ہے تو یہ یقیناً اس کی بدقسمتی ہے.356
Page 365
اس بارہ میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ : ” وہ خدا جو لاشریک
ہے جس کے سوا کوئی بھی پرستش اور فرمانبرداری کے لائق نہیں ہے.یہ اس لئے فرمایا کہ اگر
وہ لاشریک نہ ہو تو شاید اس کی طاقت پر دشمن کی طاقت غالب آ جائے.اس صورت میں خدائی
معرض خطرہ میں رہے گی.اللہ تعالیٰ کا مقام اور اس کی قدرتیں خطرے میں پڑ جائیں گی.)
اور یہ جو فرمایا کہ اس کے سوا کوئی پرستش کے لائق نہیں اس سے یہ مطلب ہے کہ وہ ایسا
کامل خدا ہے جس کی صفات اور خوبیاں اور کمالات ایسے اعلیٰ اور بلند ہیں کہ اگر موجودات میں
سے بوجہ صفات کاملہ کے ایک خدا انتخاب کرنا چاہیں یا دل میں عمدہ سے عمدہ اور اعلیٰ سے اعلیٰ خدا
کی صفات فرض کریں تو وہ سب سے اعلیٰ جس سے بڑھ کر کوئی اعلیٰ نہیں ہوسکتا، وہی خدا ہے
جس کی پرستش میں ادنی کو شریک کرنا ظلم ہے."
"
اسلامی اصول کی فلاسفی روحانی خزائن جلد 10 صفحہ 372)
پس ایک مومن کے دل میں خوف خدا پیدا ہوتا ہے جب وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ
والسلام کے اس فقرے کو سامنے رکھتے ہوئے کہ وہی خدا ہے جس کی پرستش میں ادنی کو
شریک کرنا ظلم ہے ، اپنے نفس کا جائزہ لیتا ہے.کئی باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، ہمارے
سے روزانہ ہو جاتی ہیں جس میں ہم لاشعوری طور پر بہت سی چیزوں کو خدا تعالیٰ کا شریک بنا کر
اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں.بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے اور اس کی
ربوبیت زمین و آسمان پر پھیلی ہوئی ہے.اللہ ہماری ایسی حالتوں کو اپنی مغفرت اور رحم کی
صفات سے ڈھانپ لے - لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّلِمِينَ (الأنبياء
88) کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو پاک ہے، میں یقیناً ظالموں میں سے ہوں.پس اللہ
لا إلهَ إِلَّا هُوَ کی طرف جانے کے لئے یا صحیح راہنمائی حاصل کرنے کے لئے لا إلهَ إِلَّا انْتَ
سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظلمین کی دعا بھی بڑی اہم دعا ہے جو پڑھتے رہنا چاہئے.پھر اللہ تعالیٰ یہ فرمانے کے بعد کہ اللہ ہی تمہارا معبود ہے اور حقیقی معبود ہے.فرمایا اتحی
الْقَيُّوم یعنی ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اور اپنی ذات میں قائم ہے.اور آنحی ہونے کی وجہ سے
357
Page 366
صرف خود ہی ہمیشہ زندہ نہیں رہتا بلکہ تمام جانداروں کو زندگی بخشنے والا ہے.اور القیوم ہے،
صرف خود ہی قائم نہیں ہے بلکہ کائنات کی ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے.حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ فرماتے ہیں:
اس آیت کے لفظی معنی یہ ہیں کہ زندہ خدا وہی خدا ہے اور قائم بالذات وہی خدا ہے.پس
جبکہ وہی ایک زندہ ہے اور وہی ایک قائم بالذات ہے تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ ہر ایک
شخص جو اس کے سوا زندہ نظر آتا ہے وہ اُسی کی زندگی سے زندہ ہے اور ہر ایک جو زمین یا آسمان
میں قائم ہے وہ اسی کی ذات سے قائم ہے.“
چشمہ معرفت روحانی خزائن جلد 23 صفحہ 120 )
پس اپنے زندہ اور قائم ہونے اور زندہ اور قائم رکھنے کا حوالہ دے کر مومنوں کو یہ تسلی دلا دی کہ
تم دنیاوی دباؤ اور دنیاوی لالچوں کے زیر اثر کبھی نہ آنا اور جو وعدے میں نے مومنوں سے کئے
ہیں ان پر پوری طرح یقین رکھنا.تمہاری نسلوں کی زندگی اور بقا بھی میرے ساتھ جڑے رہنے
سے وابستہ ہے اور جماعتی زندگی اور بقا بھی میرے ساتھ جڑے رہنے سے وابستہ ہے.حالات
کی وجہ سے دنیاوی ذرائع پر انحصار کرنے کا نہ سوچنے لگ جانا.میری عبادت کرتے
رہو.میری طرف جھکے رہو تو اسی میں تمہاری زندگی ہے اور اسی میں تمہاری بقا ہے.ایک دوسری جگہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ
(الفرقان 59) اور تو اس پر توکل رکھ جوزندہ ہے اور سب کو زندہ رکھتا ہے کبھی نہیں مرتا اور اس
کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح کر.پس ایک مومن حالات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات میں
کسی صفت کے بارہ میں شک میں نہیں پڑتا بلکہ مشکلات اسے حتی و قیوم اور قادر اور مجیب خدا
کے سامنے اور زیادہ جھکنے والا بناتی ہیں.پھر خدا تعالیٰ نے لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا تَوْم کہ کر یہ بھی واضح فرما دیا کہ کبھی کسی مومن کے
دل میں یہ خیال نہیں آنا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نیند یا اونگھ کی حالت میں زندہ رکھنے اور قائم رکھنے سے
غافل ہو سکتا ہے.یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی صفات نہ محدود ہیں، نہ ہی اسے کسی قسم کی کمزوری ان
358
Page 367
صفات سے عدم توجہگی کی طرف لے جاتی ہے.اس کو کسی آرام کی ضرورت نہیں.اس کی
استعدادیں انسانی استعدادوں کی طرح نہیں ہیں جنہیں ایک وقت میں آرام اور نیند کی ضرورت
ہوتی ہے.بلکہ وہ تو تمام قدرتوں کا مالک خدا ہے.اس لئے نہ ہی اسے نیند کی ضرورت ہے نہ
ہی تھکاوٹ کی وجہ سے اسے اونگھ آتی ہے.اس لئے سوال ہی نہیں کہ وہ اپنے بندوں کی زندگی
اور بقا سے کبھی غافل ہو.ہاں قانون قدرت کے تحت اور اس کی دوسری صفات کے تحت وہ
اپنے بندوں کو امتحانوں اور آزمائشوں میں ڈالتا ہے.لیکن یہ بھی اس کا اعلان ہے کہ حقیقی
زندگی اس کے بندوں کی ہی ہے.اس کے راستے میں مرنے والے بھی ہمیشہ زندہ رہتے ہیں
اور جب اس نے یہ اعلان فرمایا کہ میرے نبی کی جماعت ہی زندہ اور غالب رہنے والی ہے تو
اس بات کو بھی پورا کر کے دکھایا کہ وہ زندہ رہتی ہے اور غالب رہتی ہے.پھر فرما ياله ما في السّمواتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اسی کا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جوزمین میں
ہے.اس بات پر بھی کسی کو شبہ اور شک نہیں ہونا چاہئے کہ اگر چہ اللہ تعالیٰ نے کہا تو یہی ہے کہ
میں اور میرے رسول غالب آئیں گے.لیکن یہ کس طرح ہوگا، کیونکہ اگر دنیاوی لحاظ سے دیکھا
جائے اور وسائل کو پیش نظر رکھا جائے تو یہ غلبہ مشکل نظر آتا ہے یا بڑی دُور کی بات نظر آتی
ہے.لیکن جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ کتب الله
لا غلبن انا وَرُسُلي (المجادله (22) تو باوجود نا مساعد حالات کے اسے سچ کر دکھایا.اسی طرح جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے وعدہ فرمایا ہے تو اب بھی سچ کر
دکھائے گا اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے دیکھا بھی رہا ہے.گو انسان سوچتا ہے کہ کس طرح اور
کیونکر بظاہر اسباب اور حالات کو سامنے رکھتے ہوئے غلبہ ہوگا.یا ہوگا بھی تو بہت دُور کی بات
ہے.اور مکمل کامیابی بہت دُور کی چیز نظر آتی ہے.لیکن اللہ تعالیٰ یہاں فرماتا ہے کہ زمین و
آسمان میں جو کچھ ہے وہ خدا تعالیٰ کے تصرف اور قبضے میں ہے.یہ زمین اور آسمان بغیر مالک
کے نہیں ہیں دنیا میں رہنے والی ساری مخلوق اُسی کے قبضہ قدرت میں ہے اور وہ لامحدود اور
وسیع تر طاقتوں کا مالک ہے اور وہ ہمیشہ دنیا پر نظر رکھے ہوئے ہے.زندگی اور موت ، فنا اور بقا،
359
Page 368
اسی کے ہاتھ میں ہے.زمین کے تمام خزانے، ظاہری اور مخفی خزانے اسی کے قبضہ قدرت میں
ہیں.پس جب اس طاقت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میرے رسول کی جماعت غالب آئے گی تو
دنیا کی کوئی طاقت اس فیصلہ پر اثر انداز نہیں ہوسکتی.چاہے وہ بڑی طاقتیں ہوں یا دنیاوی
حکومتیں ہوں یا نام نہاد دین کے علمبردار ہوں.خدا تعالیٰ کے فیصلہ نے یقینا اور لازماً لاگو ہونا
ہے.لیکن مومنوں کو شروع میں ہی یہ واضح کر دیا کہ یہ غلبہ اور یہ دائمی زندگی اور بقا یقیناً ان لوگوں
کو ملے گی جو تمام صفات کے جامع خدا پر یقین رکھتے ہوں اور اس کی عبادت کرنے والے
ہوں.پس آج ہر ایک احمدی کی یہ ذمہ داری ہے جسے سمجھنا ہر ایک احمدی کے لئے انتہائی
ضروری ہے.پھر فرمایا کہ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنہ.کون ہے جو اس کے حضور سفارش
کرے مگر اس کے اذن کے ساتھ.پس اللہ تعالیٰ کے حضور کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی مگر
صرف اسے جسے اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا یا اذن دے گا.اور احادیث میں آتا ہے کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا اذن ہوگا تو آپ سفارش کریں گے.آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شفیع ہونے سے کیا مراد ہے.اس بارہ میں مختلف حوالوں سے
حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے وضاحت فرمائی ہے.ایک جگہ آپ فرماتے ہیں
کہ : ”ہاں سچا شفیع اور کامل شفیع آ نحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہوں نے قوم کو بت پرستی اور ہر
قسم کے فسق و فجور کی گندگیوں اور ناپاکیوں سے نکال کر اعلیٰ درجہ کی قوم بنادیا.“
( ملفوظات جلد دوم صفحه 160 مطبوعہ ربوہ )
پس جب حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم
شفاعت فرمائیں گے تو اس وقت ان لوگوں کی شفاعت ہوگی جو شرک سے پاک ہوں گے.ایک خدا کی عبادت کرنے والے ہوں گے.فسق و فجور سے بچنے کی کوشش کرنے والے ہوں
گے.اور اگر چھوٹی چھوٹی کمزوریوں سے جو سرزد ہو بھی جاتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ بھی آپ کی
شفاعت سے صرفِ نظر فرمائے گا.360
Page 369
اس بات کو مزید کھول کر ایک جگہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں فرمایا ہے کہ :
یہ ہرگز نہ سمجھنا چاہئے کہ شفاعت کوئی چیز نہیں.ہمارا ایمان ہے کہ شفاعت حق ہے اور اس پر
یہ نص صریح ہے.وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلونَكَ سَكَن لَّهُمْ (التوبۃ103) یہ شفاعت کا فلسفہ ہے
یعنی جو گناہوں میں نفسانیت کا جوش ہے وہ ٹھنڈا پڑ جاوے.شفاعت کا نتیجہ یہ بتایا ہے کہ گناہ کی
زندگی پر ایک موت وارد ہو جاتی ہے اور نفسانی جو شوں اور جذبات میں ایک برودت آ جاتی ہے جس
سے گناہوں کا صدور بند ہو کر ان کے بالمقابل نیکیاں شروع ہو جاتی ہیں“.(یعنی نفسانی جوشوں میں
اور جذبات میں کمی آجاتی ہے، ان میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے جس سے گناہوں
کا صادر ہونایا عمل ہونا کم ہو
جاتا ہے اور اس کے مقابلہ میں نیکیاں شروع ہو جاتی ہیں ) پس شفاعت کے مسئلے نے اعمال کو
بیکار نہیں کیا بلکہ اعمال حسنہ کی تحریک کی ہے.آپ فرماتے ہیں ” پس شفاعت کے مسئلے نے
اعمال کو بیکار نہیں کیا بلکہ اعمال حسنہ کی تحریک کی ہے.( ملفوظات جلد دوم صفحہ 702 - 701 جدید ایڈیشن)
پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس دنیا میں ہی شروع ہو گئی تھی اور یہ نیک اعمال
کے ساتھ مشروط ہے، نہ کہ کسی کفارہ سے اس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے.کفارہ کے فلسفے میں
گناہوں میں دلیری پیدا ہوتی ہے اور شفاعت کے فلسفے میں نیک اعمال کی طرف اور خدا کو
ماننے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی طرف توجہ پیدا ہوتی ہے اور اس زمانہ میں دعا کے
ذریعہ سے شفاعت کا اذن اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کو عطا فرمایا.حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ : ”میری جماعت کے اکثر
معزز خوب جانتے ہیں کہ میری شفاعت سے بعض مصائب اور امراض میں مبتلا اپنے دکھوں
سے رہائی پاگئے ہیں.“
لیکچر سیالکوٹ روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 236)
لیکن اس شفاعت کے بیان کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ خدا تعالیٰ جانتا ہے
کہ اصل حقیقت کیا ہے.يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وہ جانتا ہے جو اُن کے سامنے
361
Page 370
ہے اور جو ان کے پیچھے ہے.پس ہمارا خدا عالم الغیب ہے.اس لئے ایسے لوگ جو کھلے گناہوں میں پڑے ہوئے
ہیں ان کے بارہ میں نہ تو یہاں شفاعت کا اذن ہوتا ہے اور نہ اگلے جہان میں ہوگا.یہی قرآن
کریم سے پتہ چلتا ہے.پھر اللہ تعالیٰ اپنے علم کی وسعتوں کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرماتا ہے کہ وَلَا يُحِيطُونَ
بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمة إلا بما شاء.اس میں واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے علم کا احاطہ
کوئی نہیں کر سکتا.حتی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو خدا تعالیٰ کے محبوب ترین ہیں اور
آپ کے بارہ میں مومنوں کو حکم ہے کہ اگر تم خدا تعالیٰ کی محبت چاہتے ہو تو میرے محبوب صلی اللہ
علیہ وسلم کی پیروی کرو جن کو تمام علموں سے اللہ تعالیٰ نے بھر دیا تھا.آئندہ زمانوں کی جو بھی
خبریں قرآن کریم نے دیں وہ آپ کے ذریعہ سے آئیں اور ان کا ادراک بھی آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت عطا فرمایا.بعض باتیں ایسی ہیں جو اس زمانے میں صحابہ سمجھ نہیں
سکتے تھے لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بھی ادراک رکھتے تھے.لیکن فرمایا کہ خدا تعالیٰ
فرماتا ہے کہ یہ مکمل علم نہیں ہے.بلکہ میرے علم کی وسعتوں کو کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا.اس طرح
اللہ تعالی تلاش کرنے والوں کو چاہے روحانی مدارج اور علوم کی تلاش میں کوئی ہو یا دنیاوی علوم
کی تلاش میں کوئی ہو ، نئے راستے دکھاتا ہے، نئی منزلیں دکھاتا ہے.اور جب انسان
وہاں پہنچتا ہے تو پھر مزید راستے نظر آتے ہیں.سائنس کی ترقی بھی اس بات کی دلیل ہے کہ
خدا تعالیٰ نئے سے نئے راستے ان جستجو کرنے والوں کو دکھاتا ہے اور کائنات کی وسعتوں کا تو
شمار ہی نہیں ہے.اسی طرح روحانی مدارج ہیں.اور اللہ تعالیٰ کا علم لامحدود ہے جس کا کوئی
احاطہ نہیں کر سکتا.نہ صرف خدا تعالیٰ کی ہستی کا احاطہ نہیں ہوسکتا بلکہ اس کائنات کی پیدائش کا
بھی احاطہ نہیں کیا جاسکتا.خدا ہی ہے جب چاہتا ہے کچھ راز انسانوں پر ظاہر فرما دیتا ہے یا
کچھ علم دے دیتا ہے اور یہ بات پھر انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف پھیرنے والا بنانے والی ہونی
چاہئے جو تمام صفات کا جامع اور لامحدود ہے.362
Page 371
پھر فرمایا وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوتِ وَالْاَرْضَ کیونکہ اس کی بادشاہت زمین پر پھیلی ہوئی
ہے اور آسمان پر پھیلی ہوئی ہے.وہ تمام کائنات کی اور جتنی بھی کائناتیں ہیں ان میں موجود ہر
چیز کو زندگی دینے والا اور قائم رکھنے والا ہے.تمہارا علم محدود ہے.وہی تمہیں علم دیتا ہے.جس
حد تک استعدادوں نے ترقی کی ہے یا کوشش کی ہے اس حد تک علم دیتا ہے.لیکن یہ علم بھی
صرف اس حد تک ہے جس حد تک خدا تعالیٰ چاہتا ہے.اس لئے وہی اس بات کا حقدار ہے
کہ اس کے آگے جھکو اور تمام باطل معبودوں کو چھوڑ دو.اسی کی حکومت زمین و آسمان تک پھیلی
ہوئی ہے بلکہ اس نے اس کی حفاظت بھی اپنے ذمہ لی ہوئی ہے اور اس سے وہ تھکتا بھی نہیں.ہر چیز پر اس کی نظر ہے اور یہ ایسا وسیع اور جامع نظام ہے کہ اس کا احاطہ انسان کے لئے ممکن
نہیں ہے.اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نظر دوڑاؤ کہ شاید اللہ تعالیٰ کی پیدائش میں کوئی
نقص تلاش کر سکو لیکن ناکام ہو گے.تمہاری نظر واپس آ جائے گی.پھر نظر دوڑاؤ پھر وہ تھکی
ہوئی واپس آ جائے گی.لیکن خدا تعالیٰ وہ ذات ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے اور ازل سے چلا
رہا ہے اور بغیر کسی اونگھ اور نیند کے اور بغیر کسی تھکاوٹ کے اسے چلا رہا ہے.پس کیا یہ باتیں
تمہیں اس طرف توجہ نہیں دلاتیں کہ اس وسعتوں والے خدا کے سامنے اپنی گردنیں جھکا دو اور
سرکشی میں نہ بڑھو.اور آخر میں فرما ی وَ هُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ کہ وہ بلندشان والا اور عظمت والا ہے.اس سارے
نظام کو چلانے کے لئے اسے کسی مددگار کی ضرورت نہیں ہے.پس یہ خدا ہے جو اسلام کا خدا ہے.تمام صفات کا مالک اور جامع ہے اور یقینا وہ اس بات
کا حقدار ہے کہ اس کی عبادت کی جائے.اللہ تعالیٰ ہمیں وہ فہم و ادراک عطا فرمائے جس سے
ہم اپنے اللہ کی پہچان کرتے ہوئے ہمیشہ اس کے سامنے جھکے رہنے والے، اس کی عبادت
کرنے والے بنے رہیں اور اسے تمام صفات کا جامع سمجھتے ہوئے اس کی صفات کے کمال سے
فیض اٹھانے والے بنے رہیں.(خطبہ جمعہ حضرت خلیفہ اسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی فرموده 5 جون 2009ء ، خطبات مسرور جلد ہفتم صفحه 254 تا 262) 5ر 2009ء،خطبات 254تا262)
363
Page 372
حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز خطبه جمعه فرموده 23 اکتوبر ایدہ
2009ء میں فرماتے ہیں:
اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ولی ہے اور ولی کے تحت لغات میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی
صفات میں سے ایک صفت ہے.اس کا مطلب ہے مددگار.بعض نے اس کے یہ معنی کئے
ہیں کہ وہ ذات جو تمام عالم اور مخلوقات کے معاملات سر انجام دینے والی ہے جس کے ذریعہ
سے وہ عالم قائم ہے.اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت الوالی ہے جس کا مطلب
ہے کہ وہ ذات جو تمام اشیاء کی مالک اور اُن پر تصرف رکھنے والی ہے.ابن اثیر کہتے ہیں کہ ولایت کا حق تدبیر، قدرت اور فعل کے ساتھ منسلک ہے.اور وہ ذات
جس میں یہ امور مجتمع نہیں ہوں گے تو ان پر لفظ والی کا اطلاق نہیں ہوگا.اور پھر لسان العرب
میں یہ لکھا ہے.الولی کا مطلب ہے دوست مددگار.ابن الاعرابی کے مطابق اس سے مراد ایسا
محب ہے جو اتباع کرنے والا ہو.اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا ( سورۃ البقرہ کی آیت 258 ہے).ابو اسحق نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بارہ میں کہ مومنوں کی حاجات اور ان کے لئے
ہدایت اور ان کے لئے براہین کے قائم کرنے کے حوالے سے مددگار ہے.کیونکہ وہی ہے جو
انہیں ان کے ایمان کے لحاظ سے ہدایت میں بڑھاتا ہے، جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى (سورة محمد 18 ) اور اسی طرح وہ مومنوں کا ان کے دشمنوں کے
خلاف مددگار ہے اور مومنوں کے دین کو ان کے مخالفین کے ادیان پر غلبہ دینے والا ہے.سورۃ بقرہ کی آیت کا تھوڑا سا حصہ میں نے بتایا تھا ، یہ مکمل آیت اس طرح ہے اللہ ولی
الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَهُهُمُ الطَّاغُوتُ.يُخْرِجُونَهُم مِنَ النُّوْرِ إِلَى الظُّلُمتِ أُوْلَئِكَ أَصْحَبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَلِدُوْنَ(البقرة 258)
کہ اللہ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے.وہ ان کو اندھیروں سے نور کی طرف نکالتا
ہے.اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے دوست شیطان ہیں.وہ ان کو نور سے اندھیروں کی
364
Page 373
طرف نکالتے ہیں.یہی لوگ آگ والے ہیں وہ اس میں لمبا عرصہ رہنے والے ہیں.پس حقیقت یہی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں کا
دوست بنتا ہے یعنی ایسا ایمان جس میں دنیا کی ملونی نہ ہو.ایمان لانے کے بعد وہ اللہ کے نور کی
تلاش میں مزید ترقی کی طرف قدم بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں.انہیں پھر اللہ تعالیٰ
کامیابیاں عطا فرماتا ہے.یہاں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالنے کا مطلب ہے کہ روحانی اور جسمانی کمزوریوں
سے روحانی اور جسمانی ترقی اور مضبوطی کی طرف لے جانا.پس اللہ تعالیٰ اعلان فرما رہا ہے کہ جو
ایمان لائے اللہ تعالیٰ انہیں انفرادی طور پر بھی اور جماعتی طور پر بھی روحانی اور جسمانی کامیابیاں
عطا فرمائے گا اور ان کو تکلیفوں اور پریشانیوں سے نجات دے گا.مگر شرط ایمان لانا اور اس میں
ترقی کرنا ہے اور یہ ترقی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پڑھنے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے سے ہوتی
ہے اور جو اس طرح عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا ولی ہو جاتا ہے.کوئی
مخالف، کوئی دشمن، کوئی دنیا کی حکومت ایسے لوگوں کو ختم نہیں کر سکتی.لیکن یہاں یہ بات بھی واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومنوں پر مشکلات بھی آتی ہیں،
مصیبتیں بھی آتی ہیں.جان، مال اور اولاد کا نقصان بھی برداشت کرنا پڑتا ہے.اگر یہ سب کچھ
ہے تو پھر یہ کہنا کہ جسمانی مشکلات سے بھی نکالتا ہے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ اندھیروں سے
روشنی کی طرف لے جانے کا یہ تو مطلب لیا جا سکتا ہے کہ ایمان لانے والوں کے روحانی ترقی
میں قدم آگے بڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کا دوست ہو کر ان لوگوں کو روحانیت میں ترقی دیتا
چلا جاتا ہے اور پھر آخرت میں جیسا کہ اس نے وعدہ فرمایا ہے اجر سے نوازے گا.لیکن یاد
رکھنا چاہئے کہ مومن جب اللہ تعالیٰ پر پختہ ایمان لاتا ہے تو صرف اپنی ذات کا مفاد اور ذاتی
تکالیف اس کے پیش نظر نہیں ہوتیں بلکہ وہ جماعتی زندگی کی طرف دیکھتا ہے.بے شک ایک
مومن کو ذاتی طور پر جسمانی اور مادی اور اقتصادی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، نقصانات کا
سامنا کرنا پڑتا ہے.لیکن یہ انفرادی نقصانات بھی اگر وہ دین کی خاطر ہو رہے ہوں تو اکثر
365
Page 374
اوقات جماعتی ترقی کا باعث بنتے ہیں.اسلام کی ابتدا میں جب مکہ میں آزادی سے تبلیغ نہیں کی جاسکتی تھی اور مسلمان بڑی سخت
مظلومیت کی زندگی گزار رہے تھے.اس زمانہ میں جب مسلمانوں نے قربانیاں دیں تو کیا وہ
قربانیاں رائیگاں گئیں؟ جو مسلمان اس وقت ظلموں کا نشانہ بنائے گئے کیا وہ بے فائدہ تھے؟
نہیں، ہرگز نہیں.اس وقت بھی جب وہ مٹھی بھر مسلمان تھے، ان کی ہر قربانی ان کے
ایمانوں میں مضبوطی پیدا کرنے والی بنتی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ جماعتی ترقی کا بھی باعث بنتی
چلی جاتی تھی.اس سے تبلیغ نہیں رک گئی.مسلمان ہونا یا اسلام میں شامل ہونا اس سے رک
نہیں گیا.ظلموں کے باوجود ترقی پر قدم پڑتے چلے گئے.پھر ان ظلموں کی وجہ سے ہجرت
کرنی پڑی تو ہجرت کرنے پر اللہ تعالیٰ نے مزید ترقی کے دروازے کھولے.عددی لحاظ سے
بھی اور مالی لحاظ سے بھی مسلمان بڑھتے چلے گئے کہ وہی کفار مکہ جو ظلم کرنے والے تھے وہ
مسلمانوں کے زیرنگیں ہو گئے.جماعت احمدیہ کی تاریخ بھی دیکھ لیں.ہر ابتلا اور امتحان جہاں جماعت کی روحانی ترقی کا
باعث بنتا ہے اور بنا ہے وہاں مادی اور جسمانی ترقی کا بھی باعث بنا ہے.1974ء کے
حالات نہ ہوتے تو ایک حصہ جو ملک سے باہر نکل کر پھیلا ، وہ نہ نکل سکتا.کوئی چھوٹا موٹا
کاروبار کرنے والا تھا.کوئی معمولی زمیندارہ کرنے والا تھا.کوئی معمولی ملازمت کرنے والا
تھا.بچوں کی تعلیم کے وسائل بھی بعض کو ٹھیک طرح میسر نہیں تھے.یا وسائل تھے تو ماحول
نہیں تھا.یورپ میں آ کر کئی بچے جو ایم ایس سی اور پی ایچ ڈی کر رہے ہیں یا انہوں نے کی
ہے یا ڈاکٹر بنے ہیں، انجینئر بنے ہیں پاکستان میں انہیں کے عزیز اتنی تعلیم نہیں حاصل کر سکے
یا رجحان نہیں ہوا یا وسائل نہیں تھے.پس یہ بات باہر آئے ہوئے ہر احمدی کو ذہن میں پیدا
کرنی چاہئے کہ جہاں ان کے ایمان کی وجہ سے انہیں ملک سے نکلنا پڑا تو خدا تعالیٰ نے انہیں
بہتر حالات مہیا فرمائے اور مالی کشائش کی صورت میں ان کے معیار بدل گئے.بچوں کی اچھی
تعلیم کے لئے ماحول بھی پیدا فرمایا اور من حیث الجماعت جماعت نے مالی لحاظ سے بھی اور
366
Page 375
عددی لحاظ سے بھی ترقی کی.اسی طرح جب انفرادی طور پر تعلیمی میدان میں آگے قدم بڑھے تو
جماعت کے اندر بھی دنیاوی تعلیم کا معیار بھی بہت بلند ہوا اور یہ چیز ہر احمدی کو خدا تعالیٰ کے
مزید قریب کرنے والی ہونی چاہئے اور ایمان میں ترقی کا باعث بنانے والی ہونی چاہئے.نہ کہ
اس چیز سے کسی قسم کا تکبر یا فخر یا رعونت پیدا ہو جائے.اللہ تعالیٰ نے تو اپنے ولی ہونے کا
اظہار فرما دیا.ہم نے بھی حقیقی عبد بنتے ہوئے حقیقی عبد بننے کا نمونہ دکھانا ہے اور پھر یہ چیز
ہمیں مزید روشنیاں دکھانے والی بنتی چلی جائے گی اور پھر صرف باہر آنے والوں میں ہی ترقی
نہیں ہوئی بلکہ ان ظلموں کی وجہ سے جو 1974ء میں پاکستان میں ہوئے پاکستان میں رہنے
والوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا.جن کے کاروبار تباہ کرنے کی کوشش کی گئی تھی
اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے کاروباروں میں ترقیاں دیں جیسا کہ ہم نے ولی کے معنوں میں دیکھا
ہے.ولی دوست اور مددگار کو بھی کہتے ہیں.پس جس نے احمدیت کی خاطر قربانی دی
اللہ تعالیٰ نے اسے یا اس کی نسل کو حقیقی دوست اور مددگار بنتے ہوئے ترقیات سے نوازا.پھر دیکھیں 1984ء میں جب جماعت پر زمین تنگ کی گئی یا تنگ کرنے کی کوشش کی
گئی اور خلیفہ وقت کو وہاں سے ہجرت کرنی پڑی.تو پھر کون کام آیا ؟ وہی ولی دوست اور
مددگار جو تمام اشیاء پر تصرف رکھنے والی ذات ہے.اس وقت سفر کے دوران مختلف مواقع پر
حضرت خلیفۃ المسیح الرابع کی ایسی حفاظت اور مدد فرمائی جو کوئی بھی دنیاوی دوست نہیں کر
سکتا.پھر اس بات نے جہاں افراد جماعت کے ایمانوں میں مضبوطی پیدا کی وہاں اس ہجرت
کے نتیجہ میں جماعت کی عددی ترقی بھی ہوئی اور پھر ایم ٹی اے کی نعمت سے اللہ تعالی نے
روحانی ترقی اور تبلیغ کے سامان بھی مہیا فرمائے.ایک وقت میں دنیا میں ایک آواز سنی جاتی
ہے جو تربیت اور تبلیغ کی طرف توجہ دلانے والی ہے.پھر اس آیت میں جہاں ایمان میں ترقی کے ساتھ ساتھ جسمانی ترقی کا وعدہ کیا گیا ہے وہاں
ایمان نہ لانے والوں کے بارے میں بتایا کہ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَتُهُمُ الطَّاغُوتُ
يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلمت اور جو لوگ کافر ہیں ان کے دوست شیطان ہیں کہ وہ
367
Page 376
انہیں روشنی سے اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں.پس اللہ تعالیٰ نے یہ اصولی فیصلہ فرما دیا
کہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کا انکار کرنے والے شیطان کے دوست ہیں اور شیطان روشنی سے
اندھیروں کی طرف لے جاتا ہے.کبھی اس کے پیچھے چلنے والے روشنی کے نظارے نہیں دیکھ
سکتے.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوئی فرمایا اور مکہ والوں کو ہدایت کی طرف بلایا تو
سرداران قریش جن میں سے بعض بڑے عقلمند اور اچھے انسان کہلاتے تھے اور بعض نیکیاں بھی
کرتے تھے لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کی وجہ سے شیطان کے بہکاوے میں آ
کر، یا بہکاوے میں آنے کی وجہ سے ان نیکیوں سے محروم ہوتے چلے گئے اور آخر بلا کت ان کا
مقدر بن گئی.ابوالحکم پہلے ابو جہل بنا اور پھر ذلت کی موت ملی.گزشتہ خطبہ میں میں نے اس کا
ذکر بھی کیا تھا اور آج تک ابو جہل ہی کہلاتا ہے بلکہ تا قیامت ابوجہل ہی کہلائے گا.اس کا
ولی شیطان تھا جو اس کی کوئی مدد نہیں کر سکا.وہ اندھیروں میں ڈوبتا چلا گیا.لیکن حبشی غلام،
بلال ایمان کے نور کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ولی بن گئے اور اللہ تعالیٰ کی دوستی اور مدد کے نتیجہ
میں قیامت تک سیدنا بلال کا مقام پاگئے.اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ میں روحانیت اور سچائی کے
دعویدار ہونے کے باوجود آپ عالئیسلام کے جو منکرین تھے آپ کے مقابلہ پر کھڑے ہو کر
اندھیروں میں ڈوبتے چلے گئے.لیکن کئی ایسے جو جاہل اور اُجڑ تھے، کئی ایسے جو رشوت خور اور
بدنام زمانہ تھے، جب ان پر اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا تو وہ ایمان لانے کی وجہ سے اللہ تعالی
کے وعدے کے مطابق روحانیت میں ترقی کرنے والے بنتے چلے گئے.پس نبی کے
انکار کرنے والے اس انکار کی وجہ سے اندھیروں میں گرتے چلے جاتے ہیں اور شیطان ان میں
کینہ اور بغض اور نا انصافی اس قدر بھر دیتا ہے کہ وہ پھر مزید ظلمات میں گرتے چلے جاتے ہیں
اور پھر ان کے انجام کے بارہ میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کا انجام بہت برا ہوگا.اس دنیا
میں بھی وہ حسد کی آگ میں اور دشمنی کی آگ میں جلتے چلے جائیں گے.جماعتی ترقی کا ہر قدم
ان کے بغضوں اور کینوں کو بھڑکائے گا.لیکن ان کے یہ غصے اور کینے ان لوگوں کو جن کا ولی
اللہ تعالیٰ ہو جاتا ہے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے.368
Page 377
پھر میں لغت کے کچھ حصے کی طرف آتا ہوں.لسان میں لکھا ہے کہ بعض نے ولیم کا یہ
مطلب بیان کیا ہے کہ مومنوں کو ثواب دینا.اور ان کے نیک اعمال پر انہیں جزا دینا اللہ ہی
کے اختیار میں ہے.پھر لکھا ہے ولی اللہ، اللہ کا دوست.ولی میں مستقل مزاجی کے ساتھ اللہ کی اطاعت کرتے
ہوئے کوئی کام کرنے کا مضمون پایا جاتا ہے.اللہ تعالیٰ کا چنیدہ اور مقبول بندہ ، اللہ تعالی کے
مسلسل فضلوں اور انعامات کا مظہر ہوتا ہے.الْوَلِيُّ وَالْمَوْلٰی، اس کی گرائمر کی تفصیلات چھوڑتا
ہوں، آگے بیان ہے کہ مومن کو ولی اللہ تو کہہ سکتے ہیں لیکن مولی اللہ کہنا ثابت نہیں ہے.مگر اللہ تعالیٰ کے متعلق وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ وَمَوْلَاهُمُ دونوں طرح کہنا درست ہے.پھر انہوں
نے مختلف آیات کے حوالے سے آگے اس کی مزید وضاحت کی ہے.مثلاً ذلِكَ بِأَنَّ اللهَ مَوْلَى
الَّذِينَ آمَنُوا - سورۃ محمد کی آیت ہے.پھر نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرِ.انفال کی آیت
ہے.پھر قُلْ يَأْيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاء لِلهِ مِنْ دُونِ النَّاس سورۃ جمعہ
کی آیت میں ہے.ثُمَّ رُقُوا إِلَى اللهِ مَوْلَهُمُ الْحَق.سورۃ الانعام کی آیت ہے.وَمَالَهُمْ
مِنْ دُونِهِ مِنْ وَال- الرعد کی آیت ہے.اس میں وَالٍ کے معنی والی کے ہیں.پھر آگے
انہوں نے ان آیات کے حوالے سے گرائمر کی بحث کی ہے.تو اس بحث میں جانے کی بجائے
میں آیات کو پیش کرتا ہوں.پہلی آیت جو سورۃ محمد کی ہے وہ مکمل اس طرح ہے کہ ذلِكَ بِأَنَّ اللهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا
وَانَّ الْكَفِرِينَ لَا مَوْلى لَهُمْ (محمد (12) یہ اس لئے ہے کہ اللہ ان لوگوں کا مولیٰ ہوتا ہے جو
ایمان لائے اور کافروں کا یقیناً کوئی مولی نہیں ہوتا.اس آیت سے پہلے کی آیات میں سے
ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللهَ يَنْصُرْكُمْ
وَيُقيتُ أَقْدَامَكُمْ (محمد 8) کہ اے مومنو! اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا
اور تمہارے قدموں کو مضبوط کرے گا.اس آیت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے
زمانہ کے مسلمانوں کو بھی نصیحت ہے اور تنبیہ بھی ہے کہ صرف ایمان لانا کافی نہیں ہوگا بلکہ اللہ
369
Page 378
کے دین کی مدد تم پر فرض ہے اور یہی چیز پھر اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو سمیٹتے ہوئے تمہیں اللہ
تعالی کی مدد سے حصہ لینے والا بنائے گی.تمہارے ایمان مضبوط ہوں گے اور تم ایک جماعت
کہلاؤ گے اور خاص طور پر مسیح موعود کے زمانہ میں جب تجدید دین ہونی ہے تو مسلمانوں پر فرض
ہے کہ خدا تعالیٰ کے فرستادہ کی مدد کریں.اگر یہ مدد کریں گے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے
نظارے دیکھیں گے اور ایمان نہ لانے والوں کا پہلے انبیاء کے منکرین والا حال ہو گا.آج بھی
مسلمانوں کے لئے یہ سوچنے کا مقام ہے.میں کئی مرتبہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ
تو مدد اور نصرت کا ہے.اللہ تعالیٰ کا تو وعدہ روشنیوں کی طرف لے جانے کا ہے لیکن مومن
کہلانے کے باوجود اخباروں میں کالم نویس جو ہیں یہ لکھتے ہیں کہ ہم ایمان میں کمزوری کی
طرف بڑھ رہے ہیں.ہم روشنیوں سے اندھیروں کی طرف جارہے ہیں.ہم مادی لحاظ سے بھی
ترقی کی بجائے تنزل کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں.کون سی ایسی برائی ہے جو اس وقت ہم میں
نہیں.یہ ان کے خود اپنے لکھنے والے لکھتے ہیں.پس کہیں نہ کہیں ہم نے اس خدا کو ناراض کیا
ہوا ہے جو مومنوں کا مولیٰ ہے.اب بھی سوچنے کا وقت ہے کہ اپنے اندر ایمان کی روشنی پیدا
کریں.اللہ کے دین کی نصرت کے لئے آگے آئیں.وقت کے امام کی پہچان کریں.آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام پہنچائیں.(خطبہ جمعہحضرت خلیفة اسم الخامس ایدہ اللہ تعال فرموده 23 اکتوبر 2009ء، خطبات مسرور لدبلتم صفر 495-499)
حضرت خلیفہ اسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز خطبہ جمعہ فرمودہ 4 دسمبر 2009ء
میں سورۃ البقرہ کی آیت 258 کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں:
یا اس میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ولی ہے جو ایمان لانے والے ہیں
اور پھر اللہ تعالیٰ ولی ہونے کا حق ادا کرتے ہوئے انہیں اندھیروں سے نور کی طرف نکالتا
ہے.اس آیت کا پہلے بھی کسی خطبے میں ذکر ہو چکا ہے لیکن وہاں لفظ ولی اور اللہ تعالیٰ کی صفت
ولی کے حوالے سے یہ ذکر ہوا تھا.لیکن آج میں اللہ تعالیٰ کی جو صفت نور ہے یا لفظ نُور ہے
اس کے حوالے سے بات کروں گا.370
Page 379
لغات میں لکھا ہے کہ نور اللہ تعالیٰ کی صفات حسنہ میں سے ایک صفت ہے اور النُّور
ابن اثیر کے نزدیک وہ ذات ہے جس کے ٹور کے ذریعہ جسمانی اندھا دیکھتا ہے اور گمراہ شخص
اس کی دی ہوئی سمجھ سے ہدایت پاتا ہے.یہ معنے لسان العرب میں لکھے ہیں.پھر اسی طرح
لسان میں دوبارہ لکھا ہے کہ بعض کے نزدیک نور سے مراد وہ ذات ہے جو خود ظاہر ہے اور جس
کے ذریعے سے ہی تمام اشیاء کا ظہور ہورہا ہے.اور بعض کے نزدیک ٹور سے مراد وہ ہستی ہے
جو اپنی ذات میں ظاہر ہے اور دوسروں کے لئے بات کو ظاہر کرتی ہے.پھر لسان میں لکھا ہے، ابو منصور کہتے ہیں کہ نُور اللہ نور اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے
ہے.جیسا کہ اللہ تعالیٰ آپ فرماتا ہے اللهُ نُورُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْض (النور (36).اس آیت
کی تفسیر کرتے ہوئے بعض کا خیال ہے کہ اس کے معنی ہیں کہ اللہ ہی ہے جو آسمان میں رہنے
والوں اور زمین میں رہنے والوں کو ہدایت دینے والا ہے.اور بعض کے نزدیک مَثَلُ نُورِه
گيشكوة فِيهَا مِصْبَاح (النور (36) کا مطلب ہے کہ مومن کے دل میں اس کی ہدایت کے
نور کی مثال طاق میں رکھے ہوئے چراغ کی سی ہے.النور اس پھیلنے والی روشنی کو کہتے ہیں جو اشیاء کے دیکھنے میں مدد دیتی ہے اور یہ دو قسم کی
ہوتی ہے.دنیوی اور اخروی.پھر کہتے ہیں دنیوی نور پھر دو قسم کا ہوتا ہے.ایک وہ ٹور جس کا
ادراک بصیرت کی نگاہ سے ہوتا ہے اور یہ وہ نور ہے جو الہی امور میں بکھرا پڑا ہے جیسے نُور عقل
اور نورِ قرآن.دوسرے وہ نور جس کو جسمانی آنکھ کے ذریعہ سے محسوس کیا جاسکتا ہے.اہل لغت اس کے معنے بیان کرتے ہوئے بعض آیات کا حوالہ بھی دیتے ہیں.مثلاً نور الہی
کے متعلق اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ قَدْ جَاءَ كُم مِّنَ اللهِ نُورٌ وَكِتَبٌ مُّبِينٌ (المائدة 16)
یعنی تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹور اور کتاب مبین آچکی ہے.اسی طرح فرمایا: وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا تمشى بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَّقَلُهُ فِي الظُّلُمتِ لَيْسَ بِخَارِجِ
منها (الانعام (123) اور ہم نے اس کے لئے روشنی کی جس کے ذریعہ سے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا
ہے.کیا ایسا شخص اس جیسا ہوسکتا ہے جو اندھیروں میں ہو اور اس سے نکل نہ سکے.371
Page 380
بعض کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنا نام نور رکھا ہے تو وہ اس اعتبار سے ہے کہ وہی منور
ہے یعنی ہر چیز کو روشن کرنے والا ہے.اللہ تعالیٰ کا نام نور اس وجہ سے ہے کہ وہ یہ کام یعنی
روشن کرنا بہت زیادہ کرتا ہے.چنانچہ قرآن کریم میں آتا ہے.پھر اس آیت کی مثال دی گئی
ہے کہ اللهُ نُورُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْض یعنی اللہ ہی ہے جس کے نور سے آسمانی اور زمینی حقائق
الاشیاء کا علم ہوتا ہے اور وہ اپنے ولیوں کو پھر اس نور سے منور کرتا ہے.قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو اپنے آپ کو نُورُ السَّمواتِ وَالْأَرْضِ کہا ہے اور اس کی
مثال جیسا کہ میں نے بتایا اہل لغت نے دی ہے.تو اس آیت میں اپنے اس ٹور کی مثال دے
کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی آسمانوں اور زمین کا نور ہے.لیکن یہ ٹور انسانوں پر پڑتے ہوئے
انہیں کس طرح منور کرتا ہے.یہ سورۃ نور کی آیت ہے.یہ بھی چند ماہ پہلے میں ایک جگہ بیان
کر چکا ہوں.بہر حال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللهُ نُورُ السَّمَوتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ
كَمِشْكُوةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ
شَجَرَةٍ مُّبَرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَّا شَرِقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِي ۖ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى
نُورُ يَهْدِى اللهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
(النور (36) یعنی اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے.اس کے نور کی مثال ایک طاق کی سی ہے
جس میں ایک چراغ ہو.وہ چراغ شیشہ کے شمع دان میں ہو.وہ شیشہ ایسا ہو گویا کہ ایک چمکتا
ہوا روشن ستارہ ہے.وہ ( چراغ ) زیتون کے ایسے مبارک درخت سے روشن کیا گیا ہو جو نہ
مشرقی ہو نہ مغربی.اس (درخت) کا تیل ایسا ہے کہ قریب ہے کہ وہ از خود بھڑک کر روشن
ہو جائے خواہ اسے آگ کا شعلہ یہ بھی چھوا ہو.یہ نور علی نور ہے.اللہ اپنے نور کی طرف جسے
چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور اللہ لوگوں کے لئے مثالیں بیان کرتا ہے اور اللہ ہر چیز کا دائمی علم
رکھنے والا ہے.اس آیت کے حوالہ سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تفسیر کی روشنی میں جیسا کہ
میں نے بتایا، چند ماہ پہلے میں ایک اور مضمون کے ضمن میں بیان کر چکا ہوں.اب یہاں اس
372
Page 381
کی تفصیل تو بیان نہیں کرتا لیکن اس کا خلاصہ بیان کر کے اس مضمون کو پھر آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کے صحابہ اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے بیان کروں گا.اس نور کی جو مثال دی گئی ہے وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک ہی ہے یا اس میں
وسعت ہے.پچھلی دفعہ میں نے تفصیل بیان کی تھی.شاید بعضوں کا خیال ہو کہ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کی ذات تک محدود ہے.یقینا اللہ تعالیٰ کا نور ہر چیز پر حاوی ہے.اس آیت میں اللہ
تعالیٰ نے پہلا اعلان ہی یہ فرمایا کہ اللهُ نُورُ السَّمَوتِ وَالْأَرْض کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا
نور ہے.اس لئے ہر چیز اس کے نور سے ہی فیض پاتی ہے اور فیض پاسکتی ہے.اس کے علاوہ
کوئی نہیں جو اپنی ذاتی ہوشیاری یا علم یا عقل سے اس کے ٹور کو حاصل کر سکے.وہ خود چاہیے تو
مہیا کرتا ہے اور اس کے طریقے ہیں.یہ نور اللہ تعالیٰ کس طرح ہے اور کیوں ہے اس لئے کہ
زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا بھی وہی ہے.جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہ ذکر
فرمایا ہے کہ میں نے ہی زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے.مثلاً ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ
اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوتِ وَالْأَرْضَ (ابراهيم (33) کہ اللہ وہ ہستی ہے جس نے آسمان اور
زمین کو پیدا کیا ہے.اس میں موجود ہر چیز کو پیدا کیا اور پھر انہیں انسانوں کے لئے مسخر کیا.جب اس نے پیدا کیا تو وہی ہے جو روحانی روشنی بھی عطا فرماتا ہے اور مادی بھی.پس حقیقی نُور
اللہ تعالیٰ ہی ہے جو دیکھنے والی آنکھ کو ہر جگہ، ہر روح میں ، ہر جسم میں ، ہر چیز میں نظر آتا ہے.لیکن ایک ایسا شخص جس کی روحانی آنکھ اندھی ہوا سے یہ ٹورنظر نہیں آتا.لیکن ایک مومن اس
یقین پر قائم ہے کہ ہماری کائنات اور جتنی بھی کائناتیں ہیں جن کا علم انسان کو ہے یا نہیں ہے،
ان کا پیدا کرنے والا، ان کا نور اور ان کو قائم رکھنے والا خدا تعالیٰ ہے اور اس ٹور کا صحیح ادراک
پیدا کروانے کے لئے خدا تعالیٰ اپنے انبیاء اور فرستادوں کو بھیجتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے نُور
پاتے ہیں جو آسمان سے ان پر اترتا ہے اور وہ دنیا میں پھر اسے پھیلاتے ہیں.وہ نور جو آسمان
سے اتر کر زمین پر انبیاء کے ذریعہ سے پھیلتا ہے اس کی مثال اس آیت میں بیان فرمائی گئی ہے.جیسا کہ میں نے کہا کہ کچھ عرصہ پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ یہ نور آپ کی
373
Page 382
ذات میں کس طرح چمکا؟ میں بیان کر چکا ہوں.اور یہ اعلی ترین معیار تھا اور قیامت تک رہے گا جو
اللہ تعالیٰ کے نور کا پر تو بن کر دنیا میں قائم ہوا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹور کو زمین میں
پھیلاد یا اور پھر یہی نہیں کہ اپنی زندگی میں پھیلایا بلکہ یہ سلسلہ جاری ہے اور یہ ٹور پھیلتا چلا جارہا ہے.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جو اس کی مثال ہے وہ میں مختصر دوبارہ بیان کر دیتا
ہوں.اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کر کہ اللهُ نُورُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْض کہ اللہ زمین و آسمان کا نور ہے،
پھر فرمایا کہ انسانوں کے سمجھنے کے لئے اس کی مثال بیان کی جاتی ہے اور مثال یہ ہے.اس
کی مثال ایک مشکوۃ کی طرح ہے، ایک طاق کی طرح ہے، ایک ایسی اونچی جگہ کی طرح ہے
جس میں روشنی رکھی جاتی ہے اور یہ طاق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ ہے اور اس طاق میں
ایک مصباح ہے، ایک لیمپ ہے اور یہ لیمپ اللہ تعالیٰ کی وحی ہے جو آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم پر اتری اور یہ لیمپ ایک زجاجہ میں ہے یعنی شیشہ کے گلوب میں ہے اور یہ گلوب
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ہے جو نہایت صاف اور تمام کثافتوں سے پاک ہے اور یہ
زجاجہ یا گلوب ستارے کی طرح چمکدار ہے اور خوب روشنی بکھیر تا ہے.حضرت
مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس سے مراد آ نحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا
دل ہے جس کے اندر کی روشنی بھی بیرونی قالب پر پانی کی طرح بہتی نظر آتی ہے.پھر اللہ تعالی اپنی
مثال میں آگے بیان فرماتا ہے کہ یہ چراغ یا لیمپ زیتون کے شجرہ مبارکہ سے روشن ہے اور اس
شجرہ مبارکہ سے مراد ( یہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہم سامنے رکھیں تو ) آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے جو تمام کمالات اور برکات کا مجموعہ ہے جو تا قیامت قائم رہے گا.اس
لئے قائم رہے گا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں جو انسان کامل کہلائے اور قیامت تک
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی پیدا نہیں ہوسکتا.حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس مثال میں شرقی یا غربی نہ ہونے
سے مراد اسلام
کی تعلیم ہے.جس میں نہ افراط ہے نہ تفریط ہے.نہ ایک طرف جھکاؤ ہے.نہ
374
Page 383
سوشلزم یا کمیونزم ہے نہ کیپٹلزم ہے.بلکہ ایک درمیانی تعلیم ہے جو انسانی حقوق کو واضح کرتی
ہے.دنیا کے امن کو قائم کرتی ہے اور اس مثال میں جو یہ فرمایا کہ قریب ہے وہ تیل از خود
روشن ہو جائے تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں.اس سے مراد عقل لطیف
نورانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اسی طرح تمام اخلاق فاضلہ ہیں جو آپ کی فطرت کا حصہ بن
چکے ہیں.اور نُورٌ عَلی نُور سے مراد یہ ہے کہ ان تمام خصوصیات کے حامل انسانِ کامل پر جب
خدا تعالیٰ نے اپنا نور ڈالا یعنی تو روحی تو روحانی دنیا میں وہ نور پیدا ہوا جس کی کوئی مثال نہیں.پس یہ ہے خلاصہ اس ساری تفسیر کا جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی
ہے.پہلے بھی میں ایک دفعہ تفصیل سے بیان کر چکا ہوں.اب حقیقی نور صرف اور صرف
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہوئی شریعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اُسوہ حسنہ میں
ہے.اور تمام پرانی شریعتیں اب اس کامل انسان اور جو نُور عَلی نُور ہو چکا ہے کے آنے کے بعد
ختم ہو چکی ہیں اور اب یہی تعلیم ہے اور یہی نور ہے جو اللہ تعالیٰ کے نور سے فیضیاب کرنے والا ہے.حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقام کو جو
انسان کامل ہونے کا مقام ہے ایک جگہ اس طرح بیان فرمایا ہے.آپ فرماتے ہیں کہ : ”وہ
اعلی درجہ کا نور جو انسان کو دیا گیا یعنی انسان کامل کو.وہ ملائک میں نہیں تھا.نجوم میں نہیں
تھا ،.قمر میں نہیں تھا.آفتاب میں بھی نہیں تھا.وہ زمین کے سمندروں اور دریاؤں میں بھی
نہیں تھا.وہ لعل اور یا قوت اور زمرد اور الماس اور موتی میں بھی نہیں تھا.غرض وہ کسی چیزا رضی
اور سماوی میں نہیں تھا.صرف انسان میں تھا یعنی انسان کامل میں.جس کا اتم اور اکمل اور اعلیٰ اور
ارفع فرد ہمارے سید و مولیٰ سید الانبیاء، سید الاحیاء محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں.سو وہ نوراس
انسان کو دیا گیا.اور حسب مراتب اس کے تمام ہمرنگوں کو بھی یعنی ان لوگوں کو بھی جو کسی قدر
وہی رنگ رکھتے ہیں.اور امانت سے مراد انسانِ کامل کے وہ تمام قومی اور عقل اور علم اور دل
اور جان اور حواس اور خوف اور محبت اور عزت اور وجاہت اور جمیع نعماء روحانی وجسمانی ہیں جو
375
Page 384
خدا تعالیٰ انسان کامل کو عطا کرتا ہے.اور پھر انسانِ کامل بر طبق آیت إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ
تُؤَدُّوا الأمنتِ إِلَى أَهْلِهَا (النساء آیت : 59) اس ساری امانت کو جناب الہی کو واپس
دے دیتا ہے یعنی اس میں فانی ہو کر اس کی راہ میں وقف کر دیتا ہے......اور یہ شان اعلیٰ اور
اکمل اور اتم طور پر ہمارے سید، ہمارے مولی ، ہمارے بادی ، نبی امی ، صادق و مصدوق محمد مصطفی
صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جاتی تھی.“
( آئینہ کمالات اسلام - روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 162-160)
رض
پس یہ مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے نور سے ملا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے صحابہ میں یہ نور منتقل کر کے ان کو بھی اعلیٰ اخلاق پر قائم فرمایا.آپ نے اپنے صحابہ کو
ستاروں سے تشبیہ دی ہے کہ جن کے بھی پیچھے چلو گے تمہیں روشنی ملے گی.خدا تعالیٰ تک پہنچنے کا
راستہ ملتا ہے.عرب کے آن پڑھ کہلانے والے جولوگ تھے اس ٹور کی وجہ سے جو انہیں
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا اللہ تعالیٰ سے تعلق اور اعلیٰ اخلاق دکھانے کا ایک نمونہ بن
گئے.اللہ تعالیٰ کے نور سے اس طرح حصہ پایا کہ اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ عنہم کا تمغہ ان کے
سینے پر سجا دیا جو بعد میں آنے والوں کو بھی روشنی کی راہیں دکھانے کا باعث ہے.حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ان صحابہ کے بارہ میں فرماتے ہیں کہ وہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں محو تھے.جو ٹور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھا وہ اس اطاعت کی
نالی میں سے ہو کر صحابہ کے قلب پر گرتا اور ماسوا اللہ کے خیالات کو پاش پاش کرتا جاتا تھا.تاریکی کی بجائے ان سینوں میں نور بھرا جاتا تھا.......حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی.میرے صحابہ کے دلوں میں اللہ ہی اللہ ہے.اور اللہ تعالیٰ جو نُورُ السَّمواتِ وَالْأَرْض ہے، اس نے اپنے نور کو آ نحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور
آپ کے صحابہ کے بعد بند نہیں کر دیا.بلکہ جیسا کہ میں نے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا
یہ نور جو آپ نے خدا تعالیٰ سے لیا ہمیشہ کے لئے جاری فیض کا ایک چشمہ ہے اور اسلامی
شریعت ہی ہے جو تاقیامت جاری رہنے والی شریعت ہے.اور اللہ تعالیٰ نے آنحضرت
376
Page 385
صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق میں ڈوبنے کی وجہ سے اس زمانہ میں اس ٹور کے ساتھ جو
آسمان سے اترنے والی روحانیت کا نور ہے.اس کے ساتھ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ
والسلام کو بھیجا تا خدا تعالیٰ کے نور کا فہم و ادراک ہمارے دلوں میں بھی قائم ہو.حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ :
میں کچھ (اپنے بارے میں) بیان نہیں کر سکتا کہ کون ساعمل تھا جس کی وجہ سے یہ
عنایت الہی شامل حال ہوئی.صرف اپنے اندر یہ احساس کرتا ہوں کہ فطرتاً میرے دل کو
خدا تعالیٰ کی طرف وفاداری کے ساتھ ایک کشش ہے جو کسی چیز کے روکنے سے رُک نہیں
سکتی...66
پھر آپ فرماتے ہیں کہ : ” ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ ایک بزرگ معمر پاک صورت
مجھ کو خواب میں دکھائی دیا اور اس نے یہ ذکر کر کے کہ کسی قدر روزے انوار سماوی کی پیشوائی
کے لئے رکھنا سنت خاندان نبوت ہے.اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ میں اس سنت
اہل بیت رسالت کو بجالاؤں.سوئیں نے کچھ مدت تک التزام صوم کو مناسب سمجھا......) کتاب البریہ.روحانی خزائن جلد 13 صفحه 195 تا 197)
66
جب یہ خواب
دیکھی تو پھر آپ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ روزے رکھے جائیں.لیکن آپ نے
کہا کہ میخفی طور پر رکھے جائیں کسی کو پتہ نہ لگے اور اس کے لئے پھر آپ اپنے گھر کے باہر جو
کمرہ تھا، مردانہ جگہ تھی، اس میں منتقل ہو گئے اور وہیں کھانا وغیرہ بھی منگواتے تھے اور کھانا جو آتا
تھا اس کا اکثر حصہ یتیم بچوں میں تقسیم کر دیتے تھے اور خود معمولی سی ، تھوڑی سی غذا پر روٹی کھا کر
گزارہ کرتے تھے.اور ان روزوں کے دوران جن تجربات سے آپ گزرے ہیں اس کا بیان
کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ :
اس قسم کے روزہ کے عجائبات میں سے جو میرے تجربہ میں آئے وہ لطیف مکاشفات ہیں
جو اس زمانہ میں میرے پر کھلے.چنانچہ بعض گزشتہ نبیوں کی ملاقاتیں ہوئیں اور جو اعلیٰ طبقہ کے
اولیاء اس امت میں گزر چکے ہیں ان سے ملاقات ہوئی.ایک دفعہ عین بیداری کی حالت میں
377
Page 386
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مع حسنین علی بنی کلمن و فاطمہ رضی اللہ عنہا کے دیکھا.....اور
علاوہ اس کے انوار روحانی تمثیلی طور پر برنگ ستون سبز و سرخ ایسے دلکش و دلستاں طور پر نظر
آتے تھے جن کا بیان کرنا بالکل طاقت تحریر سے باہر ہے.وہ نورانی ستون جو سید ھے آسمان
کی طرف گئے ہوئے تھے جن میں سے بعض چمکدار سفید اور بعض سبز اور بعض سرخ تھے.ان کو
دل سے ایسا تعلق تھا کہ ان کو دیکھ کر دل کو نہایت سرور پہنچتا تھا اور دنیا میں کوئی بھی ایسی لذت
نہیں ہوگی جیسا کہ ان کو دیکھ کر دل اور روح کو لذت آتی تھی.میرے خیال میں ہے کہ وہ
ستون خدا اور بندے کی محبت کی ترکیب سے ایک تمثیلی صورت میں ظاہر کئے گئے تھے.یعنی وہ
ایک ٹور تھا جو دل سے نکلا اور دوسرا وہ ٹور تھا جو اوپر سے نازل ہوا اور دونوں کے ملنے سے ایک
ستون کی صورت پیدا ہوگئی.‘“
66
( کتاب البریہ.روحانی خزائن جلد 13 صفحه 199-198)
اور یہ سب مقام اور اللہ تعالیٰ کا آپ پر نور کا اتارنا یا اللہ تعالی کا نُوراتر نا آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کی کامل اطاعت کی وجہ سے تھا.چنانچہ ایک جگہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ الہام جس کے معنی یہ تھے کہ ملاء اعلیٰ کے
لوگ خصومت میں ہیں ( یعنی جو آسمانی فرشتے ہیں وہ آپس میں بحث کر رہے ہیں، جھگڑ رہے
ہیں ).حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں یعنی
ارادۃ الہی احیاء دین کے لئے جوش میں ہے لیکن ہنوز ملاء اعلیٰ پرشخص مخی کی تعین ظاہر نہیں
ہوئی.اس لئے وہ اختلاف میں ہے.اسی اثناء میں ( خواب میں دیکھا کہ لوگ ایک مُحیی کو
تلاش کرتے پھرتے ہیں اور ایک شخص اس عاجز کے سامنے آیا اور اشارے سے اس نے کہا
هذَا رَجُلٌ يُحِبُّ رَسُول اللہ.یعنی یہ وہ آدمی ہے جو رسول اللہ سے محبت رکھتا ہے اور اس قول
سے یہ مطلب تھا کہ شرط اعظم اس عہدہ کی محبت رسول ہے سو وہ اس شخص میں متحقق ہے.یعنی
اس میں ثابت ہے.( تذکرہ صفحہ 34 - براہین احمدیہ حصہ چہارم حاشیہ در حاشیہ نمبر 3 صفحہ 503-502 - روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 598)
378
Page 387
پس اللہ تعالیٰ نے اس زمانہ میں اپنا ٹور آپ پر اتار کر آپ کو اس زمانے میں اس نور کو
پھیلانے کے لئے کھڑا کر دیا جو آ نحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالی نے اتارا تھا اور آپ کا
یہ سب کچھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنے کی وجہ سے تھا.پس اس
محبت کی وجہ سے خدا تعالیٰ نے بھی آپ سے محبت کی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ
تعالیٰ کے اس نور کو جو زمین و آسمان پر حاوی ہے، جو روحانی انقلاب لانے کا ذریعہ بنتا
ہے، اپنے آقا کی غلامی میں آپ بھی اس ٹور کا پر تو بنے.وہ وحی جو آ نحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کے پاک سینے پر اتری تھی اس کے علوم و معارف آپ پر بھی کھولے گئے تا کہ دنیا کو بتاسکیں
کہ اس تعلیم کی اصل تفسیر یہ ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق نے کی ہے.آپ کو دنیاوی شہرت کی کوئی خواہش نہیں تھی لیکن جب اللہ تعالیٰ کا نور کسی پر پڑنے کا فیصلہ
کرتا ہے تو پھر خود خدا تعالیٰ اس کو دنیا میں شہرت دیتا ہے تا کہ وہ شخص خدا تعالیٰ کے نور کو
پھیلانے کا باعث بنے.آپ کو خدا تعالیٰ نے الہاما فرمایا کہ: ” تو اس سے نکلا اور اس نے
تمام دنیا سے تجھ کو چنا..تو جہان کا نور ہے.تو خدا کا وقار ہے.پس وہ تجھے ترک نہیں کرے
گا...اے لوگو! تمہارے پاس خدا کا نُور آیا.پس تم منکر مت ہو.“
66
( تذکرہ صفحہ 258)
پس یہ نور آپ پر اللہ تعالیٰ نے خود اتارا اور آپ کی پاک فطرت کی وجہ سے آپ کا
خدا تعالیٰ سے جو ایک تعلق قائم ہوا اور پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی وجہ سے اور
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسی کی وجہ سے وہ ٹور جوصحابہ کے ظاہری قالب پر پانی کی
طرح بہا.1400 سال بعد بھی اس نے نہ صرف حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نور
سے بھر دیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ عالئیسلام کو وہ ٹور آگے پھیلانے کا مقام بھی عطا فرمایا.حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ”میرے لئے یہ کافی تھا کہ وہ میرے
پر خوش ہو.( یعنی اللہ تعالیٰ میرے پر خوش ہے ) مجھے اس بات کی ہر گز تمنا نہ تھی ( کہ میں مسیح
موعود کہلاؤں یا مسیح ابن مریم سے اپنے تئیں بہتر ٹھہراؤں ).میں پوشیدگی کے حجرہ میں تھا اور کوئی
379
Page 388
مجھے نہیں جانتا تھا اور نہ مجھے یہ خواہش تھی کہ کوئی مجھے شناخت کرے.اس نے گوشہ تنہائی سے
مجھے جبر نکالا.میں نے چاہا کہ میں پوشیدہ رہوں اور پوشیدہ مروں.مگر اس نے کہا کہ میں تجھے
تمام دنیا میں عزت کے ساتھ شہرت دوں گا.“
(حقیقۃ الوحی.روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 153)
پس خدا تعالیٰ کا یہ طریق ہے کہ جب کسی کو اپنے نور سے سجاتا ہے تو تمام دنیا میں اس کا
اظہار بھی کروا دیتا ہے.ایک انسان کی بنائی ہوئی عام روشنی بھی جہاں روشنی ہو وہاں اپنا نشان
ظاہر کر رہی ہوتی ہے تو خدا تعالیٰ کے نور کو کس طرح چھپایا جا سکتا ہے.اللہ تعالیٰ یہ نورجب
اپنے بندے کو دیتا ہے اور جب یہ اعلان فرما دیتا ہے کہ اس کا نور یعنی اللہ تعالیٰ کا نور تمام زمین
و آسمان پر حاوی ہے تو اس سے یہ بھی مراد ہے کہ جو روحانی نور اللہ تعالیٰ کے خاص فیض سے
اس کے خاص بندوں پر آسمان سے اترا ہے اب اس کے فیض عام کا بھی سلسلہ جاری ہو گیا
ہے.پس اللہ تعالیٰ کے ان خاص بندوں سے جڑ جاؤ تو یہ ٹور پھر تمہارے دلوں کو بھی روشن کر
دے گا.چاہے چھوٹے چھوٹے طاق بنیں.چاہے چھوٹے چھوٹے گلوب ہوں.چاہے اس کی
روشنی کو پھیلانے کی ایک عام مومن کی استعدادوں کے مطابق کوئی حد مقرر ہو لیکن جو نجڑیں
گے وہ پھر اس نور سے حصہ پاتے ہوئے آگے بھی نُور کو پھیلانے والے بنتے جائیں گے لیکن
اللہ تعالیٰ کا نُور جب کسی انسان تک پہنچتا ہے، کسی مومن تک پہنچتا ہے اگر اس نے حقیقی نور
حاصل کیا ہے تو وہ اس تک پہنچ کر اسے فیضیاب کرتے ہوئے دوسروں کو فیض پہنچانے کا
باعث ضرور بنتا ہے.پس اس کے حاصل کرنے اور اس سے زیادہ سے زیادہ فیضیاب ہونے
کے لئے خدا تعالیٰ کے محبوب ترین کا اسوہ اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہئے.عبادات
میں، اخلاق میں ، عادات میں جب اس شوق سے اس اسوہ کو اختیار کرنے کی کوشش اور سوچ
ہوگی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہوگی تو اس کا
اعلان خدا تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم میں یوں کروایا ہے کہ قُل اِن
كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ الله (آل عمران (32) کہ کہہ دے کہ اگر تم اللہ سے
380
Page 389
محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو.اللہ تعالیٰ بھی پھر تم سے محبت کرے گا.پس یہ محبت تھی جو
صحابہ نے آپ سے
کی تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نور سے منور ہو گئے اور یہی محبت ہے جو اس زمانے میں
حقیقی رنگ میں حضرت
مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ہے.تو
آپ خدا تعالیٰ کے محبوب بن کر اس زمانہ میں نُور پھیلانے کا اعزاز پانے والے بن گئے.پس آج اگر کسی کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت کا دعوی ہے تو مسیح موعود سے تعلق جوڑنا
بھی ضروری ہے.یہ بھی خدا تعالیٰ کے حکموں میں سے ہے اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
حکموں میں سے ہے.آج جماعت احمد یہ ہی ہے جو اس سلسلہ تعلق کی وجہ سے خلافت سے بھی
جڑی ہوئی ہے اور اس ٹور سے بھی فیض پارہی ہے جو اللہ تعالیٰ روحانی ٹور کی صورت میں انبیاء
کے ذریعہ ظاہر فرماتا ہے اور جس کا عظیم ترین معیار اور مقام جیسا کہ میں نے کہا آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اور جس کا احیاء اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کے عاشق صادق کے ذریعہ سے فرمایا ہے.پس اب جہاں روحانی ترقیات حضرت
مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے جڑنے سے وابستہ ہیں وہاں دنیاوی امن کا قیام بھی مسیح موعود
سے ہی وابستہ ہے کیونکہ آپ نے ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو پورا فرمایا
کہ دنیا کو پیار محبت اور صلح کی طرف بلاتے ہوئے ، اسے قائم کرنے
کی تلقین کرتے ہوئے اور
خدا تعالیٰ کے حقوق قائم کرتے ہوئے ، اللہ تعالیٰ کے نور سے منور کریں اور دنیا کے امن کا
ذریعہ بن جائیں.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد تھا کہ يَضَعُ الحزب، جب مسیح آئے گا تو جنگوں کا
خاتمہ ہوگا اور اسی يَضَعُ الحزب کی وجہ سے پھر امن اور سلامتی کے پیغام بھی پھیلیں گے اور آپ
کی تعلیم کی روشنی میں ہی ، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی روشنی میں ہی دائمی سلسلہ
خلافت نے اس کو پھر آگے بڑھاتے چلے جانا ہے.حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تفسیر میں نور کی تفسیر بیان فرماتے ہوئے اس
نکتہ کو بھی بیان فرمایا ہے کہ اس ٹور کے دنیا میں انتشار کے لئے تین چیزیں ضروری ہیں.381
Page 390
نمبر ایک الوہیت، اللہ تعالیٰ کی ذات دوسرے نبوت اور تیسرے خلافت.اور جب تک مومن
اپنے اندر ایمان اور اعمال صالحہ پر توجہ دیتے رہیں گے اس چیز کو اپنے اندر قائم رکھیں گے اس ٹور
کا سلسلہ لمبا ہوتا چلا جائے گا.اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم خدا تعالیٰ کے نور سے ہمیشہ
فیضیاب ہوتے چلے جانے والے بنتے چلے جائیں اور کبھی ہم خدا تعالی کے نور سے محروم نہ ہوں.طبه جمع حضرت علی سیح الخامس ایدہ اللہ تعالی فرموده 4 دسمبر 2009ء، خطبات مسرور جلد ہفتم صفحه 561-569)
حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے نور کے مضمون کو جاری رکھتے
ہوئے 11 دسمبر 2009ء کے خطبہ جمعہ میں فرمایا:
گزشتہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ کی صفت نور کے حوالے سے مختلف لغوی معنی بیان کرنے کے
بعد اہل لغت نے اپنی وضاحتوں کے لئے جو آیات قرآنیہ درج کی ہیں ان میں سے چند آیات
کے کچھ حصے پیش کئے تھے اور سورۃ نور کی آیت الله نُورُ السَّمَوتِ وَالْأَرْضِ (النور (36) کے
حوالے سے کچھ وضاحت کی تھی.جیسا کہ میں نے کہا کہ اہل لغت نے اپنے بیان کردہ مختلف
معانی کو ثابت کرنے کے لئے آیات کے حوالے دیتے ہیں.آج کے خطبہ میں ان میں سے
ایک دو آیات کی وضاحت کروں گا جن کا حوالہ گزشتہ خطبہ میں دے چکا ہوں.میں نے بتایا تھا کہ نُور پھیلنے والی روشنی کو بھی کہتے ہیں اور یہ ٹور بھی دو قسم کا ہے.یعنی یہ
روشنی جو پھیلتی ہے مفسرین کے نزدیک آگے اس کی پھر دو قسمیں ہیں.ایک دنیوی ٹو رہے
اور دوسرا اُخروی نُور ہے.اور دنیوی ٹور پھر دو قسم کا ہے.ایک ٹور کی قسم وہ ہے جس کا ادراک
بصیرت کی نگاہ سے ہوتا ہے اس کا نام انہوں نے معقول رکھا ہے یعنی یقین اور عقل اور دانائی کی
وجہ سے یہ ٹور ملتا ہے اور الہی امور میں یہ نور عقل اور نُورِ قرآن ہے.اور دوسرا وہ نور ہے جس کو
جسمانی آنکھ کے ذریعہ محسوس کیا جاتا ہے.اس کو محسوس کہتے ہیں.جیسے وہ ٹورجو چاند اور
سورج اور ستاروں اور دیگر روشن اجسام میں پایا جاتا ہے.نُورالہی کی مثال میں مفردات کے حوالے سے میں نے سورۃ مائدہ کی آیت اور سورۃ انعام
کی آیات کا حوالہ دیا تھا.جس کی تفصیل میں نے بیان نہیں کی تھی.بہر حال جسمانی آنکھ کی
382
Page 391
جس کے ذریعہ دیکھنے والے ٹور کی مثال مفردات نے سورۃ یونس کی آیت نمبر 6 کی دی ہے.جس میں
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَا وَالْقَمَرَ نُورًا (يونس) یعنی
وہی ہے جس نے سورج کو روشن اور چاند کو منور کیا ہے.یہاں بعض کو شاید یہ الجھن ہو کہ سورج کے لئے مضیاء اور چاند کے لئے نور کا لفظ استعمال کیا
گیا ہے.اس لئے ضیاء جو ہے وہ زیادہ روشن چیز ہے اور نور کم روشن ہے.اہل لغت بھی یہی
لکھتے ہیں کہ ضیاء روشن چیز کو کہتے ہیں اور نور کم روشن کو.ضیاء نور کے مقابلے پر زیادہ طاقتور
ہے.اپنی ذات میں جو روشنی ہوتی ہے اس کو ضیاء اور ضو ء کہتے ہیں اور نور کا لفظ عمومی طور پر اس
وقت بولا جاتا ہے یا استعمال کیا جاتا ہے جب کسی غیر سے روشنی لیتی ہے.لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں فرمایا کہ اللهُ نُورُ السَّمَوتِ وَالْأَرْضِ تو اس کا کیا
مطلب ہے اس کا مفسرین نے یہ جواب دیا ہے کہ نور کے اور بھی کئی معنی ہیں اور یہ نور جو ہے
یہ ضیاء کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ نے
فرمایا ہے وَسِرَاجًا منيرا (الاحزاب (47) کہ وہ روشن سورج ہے.یعنی آپ کے ٹور سے
دوسرے لوگ روشن ہوں گے جبکہ آپ کا نور بھی اللہ تعالیٰ کے نور سے ہے.نیز لغت والے یہ
بھی لکھتے ہیں کہ ٹور ضیاء کی روشنی کو بھی کہتے ہیں، ضیاء کی شعاع کو بھی کہتے ہیں یعنی جو چیز اپنی
ذات میں روشن ہے اس روشنی کے انعکاس کو بھی نور کہتے ہیں.پس خدا تعالیٰ کے نور کی
شعاعوں کا جو انعکاس ہے یا خدا تعالیٰ کا جو انعکاس ہے یہی ہمیں مادی اور روحانی زندگی میں نظر
آتا ہے.کائنات کا حقیقی ادراک اس وقت حاصل ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ نُور
سے اُسے دیکھیں.کیونکہ ٹور ہر اس چیز کو بھی کہتے ہیں جس کے ذریعہ سے دوسری چیزیں نظر
آنے لگیں.پس خدا تعالیٰ کی ذات میں ڈوب کر ظاہری آنکھ سے بھی اس ٹور کا حقیقی رنگ میں
ادراک ہوسکتا ہے جو خدا تعالیٰ نے انسان کے لئے ظاہر کیا ہے اور انسانوں کے لئے مسخر کیا
ہے.سورج بھی اور چاند بھی اور کائنات کی ہر چیز بھی اسی طرح حقیقی طور پر نظر آ سکتی ہے جب
383
Page 392
اُسے اللہ تعالیٰ کے نور کے سامنے رکھتے ہوئے دیکھا جائے.لیکن اگر کسی دہریہ کو ان چیزوں
میں خدا نظر نہیں آتا جبکہ مومن کو تو ہر چیز میں خدا نظر آتا ہے اور وہ ان چیزوں سے فیض بھی پار با
ہے تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کی رحمانیت ہے اور پھر بعض دفعہ ان کی یا سائنسدانوں کی کوششیں بھی
اللہ تعالیٰ کی رحیمیت کے جلوے ہیں کہ انہیں خدا تعالیٰ کی بنائی ہوئی اس کائنات کی چیزوں کا
ایک حد تک علم حاصل ہو رہا ہے اور چاند اور سورج اور دوسرے ستاروں کے دنیاوی فائدے
ایک دہر یہ اٹھا رہا ہے.جبکہ مذہب کی دنیا میں رہنے والا اور ایک حقیقی مومن جسے تو ر قرآن
بھی دیا گیا ہے اس سے روحانی اور مادی دونوں طرح کے فائدے اٹھاتا ہے.خدا تعالیٰ نے
قرآن کریم میں بعض جگہ دونوں نوروں کا ایک ہی جگہ ذکر بھی فرمایا ہے تا کہ دنیاوی کاموں میں
بھی راہنمائی ملے اور روحانی کاموں کی طرف بھی توجہ پیدا ہو.پھر ٹو راخروی کے متعلق مفردات میں آتا ہے کہ ٹور اخروی کیا چیز ہے.اس کے بارہ میں
انہوں نے اس آیت کو سامنے رکھا ہے کہ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ
رَبَّنَا أَثْمِمْ لَنَا نُورَنَا (التحریم (9) اُن کا نور ان کے آگے اور داہنی طرف روشنی کرتا ہوا چل رہا
ہوگا اور وہ خدا سے التجا کریں گے کہ اے پروردگار ہمارا نور ہمارے لئے مکمل کر دے.یہ وہ
اخروی نُور ہے جوان کو مرنے کے بعد نظر آئے گا.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے يَأَهْلَ الْكِتب قَدْ جَاءَ كُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّهَا كُنْتُمْ
تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَبِ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ.قَدْ جَاءَ كُمْ مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَ كِتَبٌ مُّبِينٌ يَهْدِي بِهِ
اللهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ
إلى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ (المائدہ 16-17) اے اہل کتاب یقینا تمہارے پاس ہمارا وہ رسول آ
چکا ہے جو تمہارے سامنے بہت سی باتیں جو تم اپنی کتاب میں سے چھپایا کرتے تھے خوب
کھول کر بیان کر رہا ہے اور بہت سی ایسی ہیں جن سے وہ صرف نظر کر رہا ہے.یقینا تمہارے
پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آچکا ہے اور ایک روشن کتاب بھی.384
Page 393
اور دوسری آیت کا ترجمہ ہے کہ اللہ اس کے ذریعہ انہیں جو اس کی رضا کی پیروی کریں
سلامتی کی راہوں کی طرف ہدایت دیتا ہے اور اپنے اذن سے انہیں اندھیروں سے نور کی طرف
نکال لاتا ہے اور انہیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے.پس وہ تمام باتیں جو پہلی کتابوں میں ان کے ماننے والوں نے یا تو بدل دی تھیں یا چھپالیا
کرتے تھے.ظاہر نہیں کیا کرتے تھے ان کے بارہ میں خدا تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ اللہ
تعالیٰ سے اطلاع پا کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اب دوبارہ دنیا کے سامنے وہ باتیں پیش فرما
رہے ہیں.اور صرف یہی نہیں بلکہ یہ جو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے دنیا کے
سامنے پیش ہو رہی ہیں ان میں بہت سے نئے احکامات ہیں.بہت سی نئی باتیں ہیں.خدا تعالیٰ تک پہنچنے کے، روحانیت میں ترقی کے نئے اور وسیع راستے کھل رہے ہیں.اور ایسے
احکامات ہیں جو انسان کی فطرت کے مطابق ہیں اور جن میں کوئی افراط اور تفریط نہیں ہے.ایک
ایسا رسول آیا ہے جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے.ایک معتدل تعلیم ہے جو اسلام پیش کرتا ہے.حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہر یک وحی نبی منزل علیہ کی فطرت
کے موافق نازل ہوتی ہے.( یعنی جس نبی پر وہ وحی اتر رہی ہو اس کی فطرت کے مطابق وحی
نازل ہوتی ہے.) " جیسے حضرت موسیٰ علیکلام کے مزاج میں جلال اور غضب تھا.توریت بھی
موسوی فطرت کے موافق ایک جلالی شریعت نازل ہوئی.حضرت مسیح علیہ السلام کے مزاج
میں حلم اور نرمی تھی.سوانجیل کی تعلیم بھی حلم اور نرمی پر مشتمل ہے.مگر آ نحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کا مزاج بغایت درجہ وضع استقامت پر واقعہ تھا.“ ( ایسا بہت زیادہ ایک ایسی جگہ پر واقع تھا
جہاں نہ بختی تھی نہ نرمی تھی.فرمایا کہ نہ ہر جگہ حلم پسند تھا اور نہ ہر مقام پر غضب مرغوب خاطر
تھا.نہ ہر جگہ نرمی ظاہر کرتے تھے.نہ ہر جگہ اور موقع پر غصہ ہی ظاہر کیا جاتا تھا.بلکہ ایک
ایسا رستہ تھا جو سیدھا راستہ تھا).فرمایا کہ بلکہ حکیمانہ طور پر رعایت محل اور موقعہ کی ملحوظ طبیعت
مبارک تھی.سو قرآن شریف بھی ایسی طرز موزون و معتدل پر نازل ہوا کہ جامع شدت و رحمت،
385
Page 394
66
و ہیبت و شفقت و نرمی و درشتی ہے.“
(براہین احمدیہ.روحانی خزائن جلد اول - صفحہ 193 - حاشیہ )
چنانچہ دیکھ لیں قرآن کریم کے احکامات بھی سموئے ہوئے ہیں.مثلاً اللہ تعالیٰ ایک جگہ
فرماتا ہے جَزَاؤُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ (الشوریٰ 41) اور
بدی کا بدلہ اتنی ہی بدی ہے اور جو معاف کرے اور اصلاح کو مدنظر رکھے تو اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ
کے ذمہ ہے.پس یہ ہے اسلام کی سموئی ہوئی تعلیم جو آ نحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی
کہ سزا کا مقصد اصلاح ہے، غلط کام کرنے والے کے اخلاق کی بہتری ہے.اگر معاف
کرنے سے اصلاح ہو جاتی ہے، اخلاق میں بہتری آسکتی ہے تو معافی ہونی چاہئے.اور اگر
سزا ہی اس کی اصلاح کا ذریعہ ہے تو سزا دینا ضروری ہے.ہاں یہ ضروری ہے کہ سزا اتنی ہی
دی جائے جتنا کہ جرم ہے.کسی طرح کا بھی ظلم نہ ہو.اسلام کی تعلیم نہ تو یہ ہے کہ دائیں گال پر
تھپڑ کھا کر بایاں بھی آگے کر دو اور نہ ہی یہ ہے کہ آنکھ کے بدلے آنکھ ضرور نکالنی ہے اور
حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اب دیکھو اس آیت میں دونوں پہلوؤں کی
رعایت رکھی گئی ہے اور عفو اور انتقام کو مصلحت وقت سے وابستہ کر دیا گیا ہے.سو یہی حکیمانہ
مسلک ہے جس پر نظام عالم کا چل رہا ہے.یہ بتانے کے بعد کہ تمہارے پاس ایک رسول آیا جس نے تمام پرانی باتیں اور نئی باتیں
بھی کھول کر سامنے رکھ دیں.پھر خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ قَدْ جَائی كُم مِّنَ اللهِ نُورٌ وَكِتب
مين (المائدہ 16) یقینا تمہارے پاس ایک رسول آچکا ہے اور ایک روشن کتاب بھی.یہ
ٹو رجو یہاں بیان ہوا ہے یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں.اس کی مثال میں نے پہلے بھی پیش کی تھی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے سر اجبا
مشنیرا کہا ہے.ایک روشن چمکتا ہوا سورج کہا ہے.کیونکہ اب آپ ہی ہیں جن کے ذریعہ
سےخدا تعالیٰ کے ٹور نے آگے اپنی چمک دکھانی ہے اور اب کوئی نہیں جو اس واسطے کے بغیر
386
Page 395
اللہ تعالیٰ کی روشنی اور نور کو حاصل کر سکے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے
مطابق اور خدا تعالیٰ کے وعدے کے مطابق آخری زمانہ میں سب سے بڑھ کر اس شخص نے
اُس ٹور سے حصہ پانا تھا جسے مسیح و مہدی کا اعزاز دیا گیا اور اس حیثیت سے امتی نبی ہونے
کے خطاب سے بھی نوازا گیا.کیونکہ اب اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے انسان کامل، افضل الرسل
اور سرا جا منیراً کی مہر، جو مہر نبوت ہے یہ جس پر لگے گی اُسے پھر اللہ تعالیٰ کے نور سے بھر دے
گی.پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت نبوت خدا تعالیٰ کے نوروں کو بند کرنے
کے لئے نہیں ہے بلکہ نوروں کو مزید جلا بخشنے کے لئے اور صیقل کرنے کے لئے ہے.پس یہ
ہے مقام ختم نبوت کہ وہ ایسی روحانی روشنی ہے جو پھر اعلی ترین روشنیاں پیدا کرسکتی ہے.لیکن
یہ واضح ہو کہ جیسا کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس ٹور کے ساتھ کتاب مبین ہے جو پھر ایک
نور ہے.اس لئے اب قرآن کریم کے علاوہ جو کامل اور مکمل کتاب اور شریعت ہے کوئی اور
کتاب اور شریعت نہیں اتر سکتی.یہی ہم احمدی مانتے ہیں.حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں باتوں کو یعنی نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور
نور قرآن کریم کو اپنے ایک شعر میں یوں بیان فرمایا ہے.اس شعر سے دونوں مطلب نکلتے
ہیں.خدا تعالیٰ کا نور بھی اور قرآن کریم بھی جو خدا تعالیٰ کا کلام ہے کہ
نور لائے آسماں سے خود بھی وہ اک نور تھے
قوم وحشی میں اگر پیدا ہوئے کیا جائے عار
دشمن اعتراض کرتا ہے کہ ایک ان پڑھ اور وحشی قوم کا شخص آخری پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرتا
ہے.جو خود بھی آتی ہے پڑھا لکھا نہیں.فرمایا یہ تو کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے.یہ بات تو
آپ کے مقام کو بڑھا رہی ہے کہ آسمان سے وہ کامل نور لے کر آئے جس نے وحشیوں کو
انسان اور انسانوں کو با اخلاق اور باخدا انسان بنا دیا.اس وحشی قوم نے جب اس ٹور سے حصہ
پایا اور قرآن کریم کی تعلیم پر عمل کیا تو دنیا کی سب سے زیادہ مہذب قوم بن گئی.387
Page 396
اور ان لوگوں نے تو جنہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اور کتاب سے یہ نور پایا،
انہوں نے تو ہزار سال پہلے اپنی علمیت کا سکہ منوالیا تھا.یورپ جو آج علم کی روشنی کا اظہار کر رہا
ہے، یورپ نے ان سے علوم سیکھے تھے.پس صرف روحانی ٹورنہیں بلکہ دنیاوی ترقیات کے
لئے بھی وہ لوگ جو تھے روشنی کا مینار بن گئے.پس آج مسلمانوں کوغور کی ضرورت ہے کہ وہ ٹور
جس نے تمام دنیا کو روشن کیا، کیا دنیاوی علوم کے لحاظ سے اور کیا روحانی علوم کے لحاظ سے، وہ
ٹورکیوں ان کے اندر سے نکل کر نہیں پھیل رہا جس کے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث
ہوئے تھے اور اپنے ماننے والوں میں وہ ٹور پیدا کیا تھا.اللہ، رسول اور قرآن کی پیروی کا
دعوی ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ ٹورنظر نہیں آرہا.وجہ صاف ظاہر ہے کہ اس زمانہ میں جس شخص
نے اس ٹور کا حقیقی پر تو بنا تھا اس کا انکار ہے لیکن ساتھ ہی احمدیوں کے لئے بھی سوچنے کا اور
فکر کرنے کا مقام ہے کہ منہ سے ماننے کا دعویٰ کر کے نُور سے حصہ نہیں مل جاتا.اس قرآنی
ٹور سے حصہ لینے کے لئے اس انسان کامل کے عاشق صادق کی بیان کردہ تعلیم اور قرآنی تفسیر
پر غور کرنا اور اس کو اپنے اوپر لاگو کرنا بھی ضروری ہے.دنیا میں ڈوب کر روشنی تلاش نہ
کریں.بلکہ قرآن کریم میں ڈوب کر حکمت کے موتی تلاش کرنا ہر ایک احمدی کا فرض ہے اور
دنیا کو حقیقی روشنی سے روشناس کروانا ضروری ہے.حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے
اپنے ایک عربی شعری کلام میں آنحضرت ﷺ کے نور کو اس طرح بیان فرمایا ہے.ایک شعر
میں فرماتے ہیں کہ
نُورٌ مِّنَ اللهِ الَّذِي أَحْيَا الْعُلُوْمَ تَجَلُّ دَا
الْمُصْطَفَى وَالْمُجْتَبى وَالْمُقْتَدى وَالْمُجْتَدى
وہ اللہ کا نور ہے جس نے علوم کو نئے سرے سے زندہ کیا.وہی برگزیدہ اور چنیدہ ہے جس کی
پیروی کی جاتی ہے اور فیض طلب کیا جاتا ہے.پس علوم معارف کا خزانہ اب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور قرآن کریم ہے.لیکن
اس کو سمجھنے کے لئے آنکھ میں نور پیدا کرنے کی ضرورت ہے.جس کا پیدا کرنا اس زمانہ میں
388
Page 397
خدا تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے مجڑ کر ہی مقدر کر دیا ہے.پس خوش
قسمت ہیں وہ جو اس نور کو حاصل کرنے کے لئے آپ کی بیعت کا حق ادا کرنے والے ہیں.حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام یہ بیان فرماتے ہوئے کہ میں نے یہ مقام کس طرح
پایا، فرماتے ہیں کہ : میں ہمیشہ تعجب کی نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ یہ عربی نبی جس کا نام محمد ہے
ہزار ہزار درود و سلام اس پر ).یہ کس عالی مرتبہ کا نبی ہے.اس کے عالی مقام کا انتہا معلوم
نہیں ہو سکتا اور اس کی تاثیر قدسی کا اندازہ کرنا انسان کا کام نہیں.افسوس کہ جیسا حق شناخت کا
ہے اس کے مرتبہ کو شناخت نہیں کیا گیا.وہ توحید جو دنیا سے گم ہو چکی تھی وہی ایک پہلوان
ہے جو دوبارہ اس کو دنیا میں لایا.اس نے خدا سے انتہائی درجہ پر محبت کی اور انتہائی درجہ پر
بنی نوع کی ہمدردی میں اس کی جان گداز ہوئی.اس لئے خدا نے جو اس کے دل کے راز کا
واقف تھا اس کو تمام انبیاء اور تمام اولین و آخرین پر فضیلت بخشی اور اس کی مرادیں اس کی
زندگی میں اس کو دیں.وہی ہے جو سر چشمہ ہر ایک فیض کا ہے اور وہ شخص جو بغیر اقرار افاضہ
کے کسی فضیلت کا دعویٰ کرتا ہے وہ انسان نہیں بلکہ ذریت شیطان ہے.“ ( کہ اب جو کچھ
ہے وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہو کر ہی ہے.جو اس کے علاوہ کوئی دعویٰ کرتا
ہے وہ اللہ کا بندہ نہیں کہلا سکتا پھر وہ شیطان کی ذریت ہے.).فرمایا ” کیونکہ ہر ایک فضلیت کی کنجی اس کو دی گئی ہے اور ہر ایک معرفت کا خزانہ اس کو
عطا کیا گیا ہے جو اس کے ذریعہ سے نہیں پاتاوہ محروم از لی ہے.“ ( وہ ہمیشہ محروم رہے گا.)
ہم کیا چیز ہیں اور ہماری حقیقت کیا ہے؟ ہم کا فرنعمت ہوں گے اگر اس بات کا اقرار نہ کریں
کہ توحید حقیقی ہم نے اسی نبی کے ذریعہ سے پائی اور زندہ خدا کی شناخت ہمیں اسی کامل نبی کے
ذریعہ سے اور اس کے نور سے ملی ہے اور خدا کے مکالمات اور مخاطبات کا شرف بھی جس سے ہم
اس کا چہرہ دیکھتے ہیں اسی بزرگ نبی کے ذریعہ سے ہمیں میسر آیا ہے.اس آفتاب ہدایت کی
شعاع دھوپ کی طرح ہم پر پڑتی ہے اور اُسی وقت تک ہم منور رہ سکتے ہیں جب تک کہ ہم اس
کے مقابل پر کھڑے ہیں.“
(حقیقۃ الوحی.روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 119 118 )
389
Page 398
حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اس اقتباس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
مقام پر جو آپ عالی کام کی نظر میں ہے، روشنی پڑتی ہے.اگر فطرت نیک ہو تو آپ پر اعتراض
کرنے والوں کے لئے یہ کافی جواب ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے علیحدہ ہو کر
آپ کا کچھ بھی مقام نہیں ہے اور ہم اس وقت تک خدا تعالیٰ کے نور سے فیضیاب ہو سکتے ہیں
جب تک اُس آفتاب ہدایت کے سامنے کھڑے رہیں گے جسے خدا تعالیٰ نے سراجا
منیرا کہا ہے.سورۃ مائدہ کی دوسری آیت 17 جو میں نے پڑھی تھی اس میں تو خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ
دوٹور ہیں.ایک حضرت اقدس محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور دوسرا قرآن کریم.گزشتہ آیت کا حوالہ دیتے ہوئے اب اللہ تعالیٰ کی تقدیر نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہی دو چیزیں
ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کا ذریعہ بنیں گی اور ہیں اور یہی دو چیزیں ہیں جو سلامتی کی
راہوں کی طرف لے جانے والی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کا ذریعہ ہیں.سلامتی کی
را ہیں کیا ہیں؟ یہ خدا تعالیٰ تک پہنچنے کے یا پہنچانے کے مختلف راستے ہیں جو محفوظ طریقہ سے
خدا تعالیٰ تک پہنچاتے ہیں.ہر راستہ پر شیطان بیٹھا ہے لیکن سلامتی کی راہیں وہ ہیں جہاں اللہ
تعالیٰ تک انسان شیطان سے بچ کر پہنچ جاتا ہے اور نور سے فیض پاتا ہے.اور یہ سلامتی کی راہیں
ان کو ملتی ہیں جو خدا تعالیٰ کے فضل سے ہدایت پاتے ہوئے اس کی رضا کی تلاش میں رہتے
ہیں.اس کے قدم پھر اندھیروں سے نکل کر نُور کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں.وہ صراط مستقیم
پر چل پڑتا ہے.پس اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور اس کی روشن کتاب سے فیض پانے کے
لئے اللہ تعالیٰ کی رضا کی پیروی کی ضرورت ہے یا اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لئے ان
دونوں چیزوں سے نجڑ نا ضروری ہے.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ کی رضا کا جو
رض
اعلیٰ ترین نمونہ ہے وہ آپ کی تربیت کی وجہ سے، قوت قدسی کی وجہ سے آپ کے صحابہ نے
دکھایا.اور وہ لوگ پھر صرف اندھیروں سے روشنی کی طرف ہی نہیں آئے بلکہ انہوں نے
رَضِيَ الله عنہم کا اعزاز پایا.پس صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان ٹوروں سے فیض پا کر
390
Page 399
ہمارے لئے اسوہ حسنہ بن گئے.ان کے بارہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ
ستاروں کی مانند ہیں جن سے تم راستوں کی طرف راہنمائی حاصل کرتے ہو.پس یہ لوگ بھی وہ
تھے جو صراط مستقیم پر چل کر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے بن گئے.پس کیا خوش قسمت
تھے وہ لوگ جنہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست فیض پایا اور اندھیروں سے
نور کی طرف جانے کی منزلیں جلد جلد طے کرتے چلے گئے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے
بن گئے.اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق آخری زمانے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم کے عاشق صادق
کو بھیجا جس کو پھر اپنے آقا و مطاع کے نُور کا پر تو بنا دیا.حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں
مصطفی پر تیرا بے حد ہو سلام اور رحمت
اُس سے یہ نور لیا بارِ خدایا ہم نے
اور آپ عالئیسلام پر جب اس ٹور کی انتہا ہوئی تو آپ عالئیسلام سے براہ راست فیض پانے والے
بھی اپنے دلوں کو ٹور سے بھرتے ہوئے صراط مستقیم پر قائم ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل
کرنے والے بن گئے.توحید کا قیام کرنے والے بن گئے.اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو صراط مستقیم
کی دعا سکھائی ہے تو اس کے لئے اپنی اپنی استعدادوں کے مطابق اس نور سے فیض حاصل
کرنے کی کوشش بھی کرنی چاہئے.حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہی فرمایا ہے کہ ہر ایک کو اپنی اپنی
استعدادوں کے مطابق نور ملتا ہے، کسی کو کم اور کسی کوزیادہ لیکن ملتا ضرور ہے.نور سے فائدہ
ہر انسان ضرور اٹھاتا ہے.ہر مومن اٹھاتا ہے جو نیک نیتی سے اس کی طرف بڑھے گا.اللہ
تعالیٰ کسی کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا.اس لئے یہ نہیں فرمایا کہ ہر ایک نے بہر حال
اس مقام تک پہنچنا ہے جو اعلیٰ ترین مقام ہے.لیکن کوشش کا حکم ہے.جس کے لئے پوری
طرح کوشش ہونی چاہئے.بے شک صراط مستقیم کی طرف اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دیتا ہے اور
اس کے لئے اس نے ہمیں دعا بھی سکھائی ہے جو ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں لیکن اس
391
Page 400
کے لئے کوشش کا بھی حکم ہے.فرمایا کہ صراط مستقیم پر چلنے کے لئے نور کی ضرورت ہے اور
نُور اللہ تعالیٰ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم سے حاصل ہوگا اور جو اس کے
حصول کی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ پھر ایسے شخص کو صراط مستقیم پر چلاتے ہوئے اس ٹور سے
فیض حاصل کرنے والا بنا تا چلا جائے گا.(خطبہ جمعہحضرت خلیفة اسم الخامساید ال عالی فرموده 1 رمبر 2009،خطبات مسرود جلد ختم صفح 570تا577)
حضرت خلیفہ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے خطبہ جمعہ فرمودہ 02 فروری
2018ء میں سورۃ المومن کی ابتدائی آیات اور آیت الکرسی کی تلاوت اور ترجمہ کے بعد فرمایا:
ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی بعض صفات کا ذکر کیا گیا ہے اور اس کی شان اور عظمت بیان
کی گئی ہے.ان آیات کی اہمیت کے بارے میں احادیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا
ارشاد ملتا ہے.حضرت ابوہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا کہ جس نے صبح کے وقت لحم - المؤمن سے لے کر إِلَيْهِ الْمَصِيرُ تک پڑھا اور
آیتہ الکرسی بھی پڑھی تو ان دونوں کے ذریعہ سے اس کے شام کرنے تک کی حفاظت کی جائے
گی اور جس نے یہ دونوں شام کے وقت پڑھیں تو ان کے ذریعہ اس کے صبح کرنے تک
حفاظت کی جائے گی.( سنن الترمذی ابواب فضائل القرآن باب ما جاء في سورة البقرة وآية الكرسى حديث 2879)
حضور ایدہ اللہ نے پہلے سورۃ المومن کی ابتدائی آیات کی نہایت پر معارف تشریح و تفسیر کی
اور اس کے بعد فرمایا:
پھر دوسری آیت ہے جس کی طرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اس طرح
بھی توجہ دلائی ہے جو آیتہ الکرسی کے بارے میں ہے.حدیث میں ذکر ملتا ہے یہ حضرت
ابوھریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کا ایک کو ہان ہوتا
ہے اور قرآن کریم کا کو بان سورۃ بقرہ ہے.اور اس میں ایک ایسی آیت ہے جو قرآن کریم کی
رض
392
Page 401
سب آیتوں کی سردار ہے اور وہ آیت الکرسی ہے.( سنن الترمذی ابواب فضائل القرآن باب ما جاء في فضل سورة البقرة وآية الكرسى حديث 2878)
اس کی وضاحت میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ :
الله لا إله إلا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ.یعنی وہی خدا ہے اس کے سوا کوئی نہیں.وہی ہر
ایک جان کی جان اور ہر ایک وجود کا سہارا ہے.اس آیت کے لفظی معنی یہ ہیں کہ زندہ وہی خدا
ہے اور قائم بالذات وہی خدا ہے.پس جبکہ وہی ایک زندہ ہے اور وہی ایک قائم بالذات ہے
تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ ہر ایک شخص جو اس کے سوا زندہ نظر آتا ہے وہ اسی کی زندگی سے
زندہ ہے اور ہر ایک جوز مین یا آسمان میں قائم ہے وہ اسی کی ذات سے قائم ہے“.چشمه معرفت، روحانی خزائن جلد 23 صفحه 120 )
پھر مزید وضاحت فرماتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ ”جاننا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کے
قرآن شریف نے دو نام پیش کئے ہیں.اٹھتی اور الْقَيُّوم - الحتی کے معنی ہیں خود زندہ اور
دوسروں کو زندگی عطا کرنے والا.القیوم.خود قائم اور دوسروں کے قیام کا اصلی باعث.ہر
ایک چیز کا ظاہری، باطنی قیام اور زندگی انہی دونوں صفات کے طفیل سے ہے.پس کسی کا لفظ
چاہتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے“.( یہ غور طلب ہے.) حتی کا لفظ چاہتا ہے کہ اس کی
عبادت کی جائے.جیسا کہ اس کا مظہر سورۃ فاتحہ میں ايّاكَ نَعْبُدُ ہے اور الْقَيُّوم چاہتا ہے کہ
اس سے سہارا طلب کیا جاوے.اس کو ايَّاكَ نَسْتَعِينُ کے لفظ سے ادا کیا گیا ہے“.( زندہ
رہنا ہے.روحانی طور پر بھی زندہ رہنا ہے اور کئی صفت سے فائدہ اٹھانا ہے تو اس کی عبادت
کرنا ضروری ہے اور عبادت کے لئے مدد بھی اس سے مانگنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق
دے کہ ہم عبادت کرنے والے ہوں.) فرمایا کہ حق کا لفظ عبادت کو اس لئے چاہتا ہے کہ
اس نے پیدا کیا اور پھر پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا.جیسے مثلاً معمار جس نے عمارت کو بنایا ہے
اس کے مرجانے سے عمارت کا کوئی حرج نہیں ہے.‘ (ایک شخص ہے جس نے کوئی
بلڈنگ تعمیر کی ہے.اس کے مرجانے سے اس بلڈنگ کو کوئی فرق نہیں پڑتا ).مگر انسان کو
خدا کی ضرورت ہر حال میں لاحق رہتی ہے.( انسان کو خدا کی ضرورت ہر حال میں لاحق رہتی
66
393
Page 402
ہے ) اس لئے ضروری ہوا کہ خدا سے طاقت طلب کرتے رہیں اور یہی استغفار ہے“.( ملفوظات جلد 3 صفحہ 217.ایڈیشن 1985 ، مطبوعہ انگلستان)
استغفار کے مضمون کی وضاحت پہلے تفصیل سے ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیض کی روشنی کو
مسلسل جاری رکھنے کے لئے استغفار کی ضرورت ہے اور یہ استغفار ہی عبادت ہے اور اس
سے طاقت عطا ہوتی ہے.پھر آیتہ الکرسی میں جو شفاعت کا مضمون بیان ہوا ہے اس کو بیان فرماتے ہوئے یہ نکتہ آپ
نے بیان فرمایا کہ ہر انسان دوسرے کے لئے جب دعا کرتا ہے تو یہ بھی ایک طرح کی شفاعت
ہے.اور یہ ایک مومن کی صفت ہونی چاہئے جو ہمیشہ وہ کرتا رہے.آپ فرماتے ہیں:
”خدا کے اذن کے سوا کوئی شفاعت نہیں ہوسکتی.(اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے.)
قرآن شریف کی رُو سے شفاعت کے معنی یہ ہیں کہ ایک شخص اپنے بھائی کے لئے دعا کرے
کہ وہ مطلب اس کو حاصل ہو جائے یا کوئی بلاٹل جائے.“ ( یعنی جس مقصد کے لئے کسی دعا
کے لئے کہا ہے اس کے لئے دعا کرے کہ وہ مقصد اس کا پورا ہو جائے.اگر مصیبت اور بلا
ہے تو وہ بلائل جائے.) فرمایا کہ "پس قرآن شریف کا حکم ہے کہ جو شخص خدائے تعالیٰ کے
حضور میں زیادہ جھکا ہوا ہے وہ اپنے کمزور بھائی کے لئے دعا کرے کہ اس کو وہ مرتبہ حاصل ہو.یہی حقیقت شفاعت ہے.سو ہم اپنے بھائیوں کے لئے بیشک دعا کرتے ہیں کہ خدا ان کو
قوت دے اور ان کی بلا دُور کرے اور یہ ایک ہمدردی کی قسم ہے“.(نسیم دعوت ، روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 463)
پھر آپ نے فرمایا کہ چونکہ تمام انسان ایک جسم کی طرح ہیں اس لئے خدا نے ہمیں بار بار
سکھلایا ہے کہ اگر چہ شفاعت کو قبول کرنا اس کا کام ہے مگر تم اپنے بھائیوں کی شفاعت میں یعنی
ان کے لئے دعا کرنے میں لگے رہو.اور شفاعت سے یعنی ہمدردی کی دعا سے باز نہ رہو کہ
تمہارا ایک دوسرے پر حق ہے“.(ایک دوسرے کے لئے دعا کرنا ایک دوسرے پر حق
ہے.اصل میں شفاعت کا لفظ شفع سے لیا گیا ہے.شفع بجفت کو کہتے ہیں جو طاق کی ضد
394
Page 403
ہے.پس انسان کو اس وقت شفیع کہا جاتا ہے جبکہ وہ کمال ہمدردی سے دوسرے کا بجفت ہو کر
اس میں فنا ہو جاتا ہے اور دوسرے کے لئے ایسی ہی عافیت مانگتا ہے جیسا کہ اپنے نفس کے
لئے.اور یادر ہے کہ کسی شخص کا دین کامل نہیں ہوسکتا جب تک کہ شفاعت کے رنگ میں
ہمدردی اس میں پیدا نہ ہو.(انتہائی ہمدردی ہونی چاہئے ایک دوسرے کے لئے.)
فرمایا بلکہ دین کے دو ہی کامل حصے ہیں.ایک خدا سے محبت کرنا اور ایک بنی نوع سے اس
قدر محبت کرنا کہ ان کی مصیبت کو اپنی مصیبت سمجھ لینا اور ان کے لئے دعا کرنا جس کو دوسرے
لفظوں میں شفاعت کہتے ہیں“.(نسیم دعوت، روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 464)
یہ ایک نکتہ ہے جسے آیۃ الکرسی پڑھتے وقت ہم سامنے رکھیں تو بنی نوع انسان کی ہمدردی کے
لئے جذبات بڑھیں گے.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمیں یہ پڑھنے کی تلقین فرمائی تو اس میں ایمان لانے
والوں کے آپس کے ہمدردی کے تعلقات قائم کرنے کے لئے بالخصوص ارشاد ہے اور بنی نوع
انسان کے لئے بالعموم توجہ دلاتی ہے کہ ہر ایک کے لئے ہمدردی کا جذ بہ تمہارے دل میں ہونا
چاہئے لیکن بد قسمتی ہے کہ مسلمان آجکل آپس میں ہی ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں
اور دعویٰ یہ ہے کہ ہم قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والے ہیں.بہر حال یہ بھی یادر ہنا چاہئے کہ
حقیقی شفاعت کا حق اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا اور اس کے نظارے
آپ کی زندگی میں ہم نے دیکھے.چنانچہ اس کو بیان کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام
فرماتے ہیں کہ :
آخرت کا شفیع وہ ثابت ہو سکتا ہے جس نے دنیا میں شفاعت کا کوئی نمونہ دکھلایا ہو.آخرت میں بھی وہی شفیع ہوگا.یہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا ہے کہ وہ
شفاعت کریں گے کہ وہی ثابت ہو سکتا ہے جس نے دنیا میں بھی کوئی شفاعت کا نمونہ دکھلایا
ہو.) ”سواس معیار کو آگے رکھ کر جب ہم موسیٰ پر نظر ڈالتے ہیں تو وہ بھی شفیع ثابت ہوتا ہے.395
Page 404
کیونکہ بارہا اس نے اترتا ہوا عذاب دعا سے ٹال دیا.اس کی توریت گواہ ہے.اسی طرح جب
ہم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر ڈالتے ہیں تو آپ کا شفیع ہونا اجلی بدیہیات معلوم
ہوتا ہے.( یعنی بہت واضح اور صاف طور پر، روشن طور پر نظر آتا ہے.) ” کیونکہ آپ کی
شفاعت کا ہی اثر تھا کہ آپ نے غریب صحابہ کو تخت پر بٹھادیا.اور آپ کی شفاعت کا ہی اثر تھا
کہ وہ لوگ باوجود اس کے کہ بت پرستی اور شرک میں نشو نما پایا تھا ایسے موحد ہو گئے جن کی
نظیر کسی زمانے میں نہیں ملتی.اور پھر آپ کی شفاعت کا ہی اثر ہے کہ اب تک آپ کی پیروی
کرنے والے خدا کا سچا الہام پاتے ہیں.خدا ان سے ہمکلام ہوتا ہے.مگر مسیح ابن مریم میں یہ
تمام ثبوت کیونکر اور کہاں سے مل سکتے ہیں“.فرمایا کہ ”ہمارے سید و مولیٰ محمد مصطفی صلی اللہ
علیہ وسلم کی شفاعت پر اس سے بڑھ کر اور زبردست شہادت کیا ہوگی کہ ہم اس جناب کے
واسطے سے جو کچھ خدا سے پاتے ہیں ہمارے دشمن وہ نہیں پاسکتے.اگر ہمارے مخالف اس
امتحان کی طرف آویں تو چند روز میں فیصلہ ہوسکتا ہے.“
عصمت انبیاء ، روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 699-700)
پھر آیتہ الکرسی کے آخر میں اللہ تعالیٰ کی جو دو صفات بیان کی گئی ہیں یعنی علی.انتہائی بلند
شان والا اور اس سے بلند کسی کی شان نہیں ہے.وہی زمین و آسمان کا مالک ہے.اور وہ عظیم
ہے.اس کی عظمت اور بڑائی اور بلند شان کا وہ مقام ہے جس تک کوئی نہیں پہنچ سکتا.اس کی
بلند شان ہر چیز کا احاطہ کئے ہوئے ہے.کوئی چیز اس کے دائرے اور احاطے سے باہر نہیں
ہے.علی ہونا یہ اس کی بلندشان ہے.اور عظیم ہونا اس کے یہ معنی ہیں کہ اس کی عظمت اور
بڑائی اور بلند شان کا مقام ہے جس تک کوئی پہنچ نہیں سکتا.یہ عظیم ہونے کے معنی ہیں.اور
عظیم ہونے کے یہ بھی معنی ہیں کہ ہر چیز کا احاطہ کئے ہوئے ہے.کوئی چیز اس کے دائرے
اور احاطے سے باہر نہیں ہے.یہ ہے اس کی عظمت اور بلندی.اس آیت کے آخری حصہ کی وضاحت فرماتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلا
فرماتے ہیں کہ :
396
Page 405
”خدا تعالیٰ کی کرسی کے بارے میں یہ آیت ہے وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوتِ
وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.یعنی خدا کی کرسی کے اندر تمام
زمین و آسمان سمائے ہوئے ہیں اور وہ ان سب کو اٹھاتے ہوئے ہے.ان کے اٹھانے سے
وہ تھکتا نہیں ہے.اور وہ نہایت بلند ہے.کوئی عقل اس کی گنہ تک پہنچ نہیں سکتی.اور نہایت
بڑا ہے.اس کی عظمت کے آگے سب چیزیں بیچ ہیں.یہ ہے ذکر کرسی کا اور یہ محض ایک
استعارہ ہے جس سے یہ جتلانا منظور ہے کہ زمین و آسمان سب خدا کے تصرف میں ہیں اور ان
سب سے ان کا مقام دُور تر ہے اور اس کی عظمت نا پیدا کنار ہے.“
چشمه معرفت، روحانی خزائن جلد 23 صفحہ 118 حاشیہ)
پس یہ وہ عظیم خدا ہے جس کی عظمت کا کوئی کنارہ نہیں ہے اور جس کی حدود لامحدود ہیں.اس نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے.اس کی کوئی حد نہیں ہے.اور ہر چیز اس کے احاطے میں
ہے.ہر چیز کو اس نے گھیرا ہوا ہے.پس جب انسان کو ان باتوں کی سمجھ ہوگی اور یہ سمجھ کر
انسان آیات پڑھے تو تبھی اللہ تعالیٰ کی آغوش میں آسکتا ہے.اس کی حفاظت میں آجاتا ہے.جب انسان اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر انسان اللہ تعالیٰ کے
حقوق بھی اور بندوں کے حقوق بھی ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کرنی چاہئے.اور جب یہ
حقوق ادا ہور ہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ بھی پھر حفاظت فرماتا چلا جاتا ہے.پس یہ مضمون ہے جسے ہمیں اپنے سامنے رکھتے ہوئے آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ
تلقین فرمائی ہے کہ جو یہ آیات پڑھے وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہے گا.تو آیات صرف
پڑھنا ہی کافی نہیں ہے بلکہ اس کے مضمون پر غور کرتے ہوئے ان باتوں کو اپنانے کی بھی
ضرورت ہے اور وہ نہم اور ادراک حاصل کرنے کی بھی ضرورت ہے جو ان آیتوں کے بارے
میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا.قرآن کریم نے اس کی وضاحت کئی جگہ پر کی.اور
پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کھول کر ہمارے سامنے رکھا.اگر یہ باتیں
ہوں گی تو پھر انسان خدا تعالیٰ کے فضل سے اس کی حفاظت میں رہے گا.اللہ تعالیٰ ہمیں اس
397
Page 406
کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.“
خطبہ جمعہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید « اللہ تعالی فرمودہ 02 فروری 2018ء)
398....
Page 407
سورة البقرة آيات 285 تا 287
XXXX
لِلهِ مَا فِي السَّمَوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ 285.جو کچھ (بھی) آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ ہی
کا ہے اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے خواہ تم اسے ظاہر
تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ
کر دیا اسے چھپائے رکھو اللہ تم سے اس کا حساب لے گا.يُحَاسِبُكُمُ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ پھر جسے چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا عذاب
وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ دے گا اور اللہ ہر ایک چیز پر بڑا قادر ہے.قَدِيرٌ
وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَبِكَتِهِ
امَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهِ 286.جو کچھ بھی اس رسول پر اس کے رب کی طرف
سے نازل کیا گیا ہے اس پر وہ (خود بھی) ایمان رکھتا
ہے اور (دوسرے ) مومن بھی ( ایمان رکھتے ہیں).وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ یہ سب ( کے سب) اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس
رُّسُلِهِ وَ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں
غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَ إِلَيْكَ الْمَصِيرُ
اور کہتے ہیں کہ ) ہم اس کے رسولوں میں سے ایک
(دوسرے) کے درمیان (کوئی) فرق نہیں کرتے.اور یہ (بھی) کہتے ہیں کہ ہم نے (اللہ کا حکم ) سن لیا
ہے اور ہم اس کے دل سے فرمانبردار ہو چکے ہیں.( یہ لوگ دعائیں کرتے ہیں کہ) اے ہمارے رب!
ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں اور تیری ہی طرف
( ہمیں) کوٹنا ہے.لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا 287.اللہ کسی شخص پر سوائے اس ( ذمہ داری )
كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا کے جو اس کی طاقت میں ہو کوئی ذمہ داری نہیں
ڈالتا.جو اس نے (اچھا ) کام کیا ہو (وہ) اس
تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا کے لئے ( نفع مند ) ہوگا.اور جو اس نے (برا)
399
Page 408
تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى کام کیا ہو ( وہ ) اسی پر ( وبال ہو کر ) پڑے گا.الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ) اے ہمارے رب ! اگر
کبھی ہم بھول جائیں یا غلطی کر بیٹھیں تو ہمیں سزا نہ
وقفة
طَاقَةَ لَنَابِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا
وقفة
وقفة
وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلُنَا فَانْصُرْنَا عَلَى
الْقَوْمِ الْكَفِرِينَ
دیجیو.اے ہمارے رب! اور تُو ہم پر (اس طرح)
ذمہ داری نہ ڈالیو جس طرح تو نے ان لوگوں پر جو ہم
سے پہلے ( گذر چکے ) ہیں ڈالی تھی.اے ہمارے
رب! اور اسی طرح ہم سے ( وہ بوجھ نہ اٹھوا جس
(کے اٹھانے ) کی ہمیں طاقت نہیں اور ہم سے
در گذر کر.اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر
( کیونکہ ) تو ہمارا آتا ہے.پس کافروں کے گروہ
کے خلاف ہماری مدد کر.400
Page 409
حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سورة البقرہ کی آیت 286 درج کرنے کے بعد
فرماتے ہیں:
یعنی رسول اور اُس کے ساتھ کے مومن اس کتاب پر ایمان لائے ہیں جو اُن پر نازل
کی گئی اور ہر ایک خدا پر ایمان لایا اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اُس کے
رسولوں پر اور اُن کا یہ اقرار ہے کہ ہم خدا کے رسولوں میں تفرقہ نہیں ڈالتے اس طرح پر کہ بعض
کو قبول کریں اور بعض کورڈ کردیں بلکہ ہم سب کو قبول کرتے ہیں.ہم نے سنا اور ایمان
لائے.اے خدا! ہم تیری بخشش مانگتے ہیں اور تیری طرف ہی ہماری بازگشت ہے.ان تمام آیات سے ظاہر ہے کہ قرآن شریف ان تمام نبیوں کا ماننا جن کی قبولیت دنیا میں
پھیل چکی ہے مسلمانوں کا فرض ٹھہراتا ہے اور قرآن شریف کی رُو سے ان نبیوں کی سچائی کے
لئے یہ دلیل کافی ہے کہ دنیا کے ایک بڑے حصہ نے اُن کو قبول کیا اور ہر ایک قدم میں خدا کی
مدد اور نصرت اُن کے شامل حال ہو گئی.خدا کی شان اس سے بلند تر ہے کہ وہ کروڑ با انسانوں کو
اُس شخص کا سچا تابع اور جان نثار کرے جس کو وہ جانتا ہے کہ خدا پر افترا کرتا ہے اور دنیا کو دھوکا
دیتا ہے اور دروغ گو ہے.اور اگر کاذب کو ایسی ہی عزت دی جائے جیسا کہ صادق کو تو امان
اُٹھ جاتا ہے اور امر نبوت صادقہ مشتبہ ہو جاتا ہے.پس یہ اصول نہایت صحیح اور سچا ہے کہ جن نبیوں کو قبولیت دی جاتی ہے اور ہر ایک قدم میں
حمایت اور نصرت الہی اُن کے شامل حال ہو جاتی ہے وہ ہر گز جھوٹے ہوا نہیں کرتے.ہاں!
ممکن ہے کہ پیچھے آنے والے اُن کے نوشتوں میں تحریف تبدیل کردیں اور اپنی نفسانی
تفسیروں سے اُن کے مطالب کو الٹادیں بلکہ پرانی کتابوں کے لئے یہ بھی ایک لازمی امر ہے
کہ مختلف خیالات کے آدمی اپنے خیال کے طور پر اُن کے معنی کرتے ہیں اور پھر رفتہ رفتہ وہی
401
Page 410
معنے جزو کتاب کی سمجھے جاتے ہیں اور پھر انہیں مختلف خیالات کی کشش کی وجہ سے کئی فرقے
ہو جاتے ہیں اور ہر ایک فرقہ دوسرے فرقہ کے مخالف معنی کرتا ہے.چشمه معرفت، روحانی خزائن جلد 23 صفحه 377، 378)
لا يُكلف اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا یعنی خدا تعالیٰ انسانی نفوس کو ان کی وسعت علمی سے
زیادہ کسی بات کو قبول کرنے کے لئے تکلیف نہیں دیتا اور وہی عقیدے پیش کرتا ہے جن کا
سمجھنا انسان کی حد استعداد میں داخل ہے تا اس کے حکم تکلیف مالا يطاق میں داخل نہ ہوں.اسلامی اصول کی فلاسفی ، روحانی خزائن جلد 10 صفحه 432)
ہمیں حکم ہے کہ تمام احکام میں ، اخلاق میں ، عبادات میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
پیروی کریں پس اگر ہماری فطرت کو وہ قوتیں نہ دی جاتیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
تمام کمالات کو ظلی طور پر حاصل کر سکتیں تو یہ حکم ہمیں ہر گز نہ ہوتا کہ اس بزرگ نبی کی پیروی
کرو کیونکہ خدا تعالیٰ فوق الطاقت کوئی تکلیف نہیں دیتا جیسا کہ وہ خود فرماتا ہے : لا يُكلف
اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا.(حقیقۃ الوحی، روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 156 )
ا جس پر خدا تعالیٰ کے نزدیک...اتمام حجت ہو چکا ہے وہ قیامت کے دن مؤاخذہ کے
لائق ہوگا اور جس پر خدا کے نزدیک اتمام حجت نہیں ہوا اور وہ مکذب اور منکر ہے تو گوشریعت
نے (جس کی بنا ظاہر پر ہے ) اُس کا نام بھی کافر ہی رکھا ہے اور ہم بھی اُس کو باتباع شریعت
کافر کے نام سے ہی پکارتے ہیں مگر پھر بھی وہ خدا کے نزدیک بموجب آیت لَا يُكَلِّفُ اللهُ
نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا قابل مواخذہ نہیں ہوگا.ہاں ! ہم اس بات کے مجاز نہیں ہیں کہ ہم اُس کی
نسبت نجات کا حکم دیں.اس کا معاملہ خدا کے ساتھ ہے، ہمیں اس میں دخل نہیں.(حقیقۃ الوحی ، روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 186)
ہم کو عقل سے بھی کام لینا چاہئے کیونکہ انسان عقل کی وجہ سے مکلف ہے.کوئی آدمی بھی
خلاف عقل باتوں کے مانے پر مجبور نہیں ہو سکتا.قومی کی برداشت اور حوصلہ سے بڑھ کر کسی قسم
کی شرعی تکلیف نہیں اٹھوائی گئی.لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا.اس آیت سے صاف
402
Page 411
طور پر پایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام ایسے نہیں جن کی بجا آوری کوئی کر ہی نہ سکے.اور نہ
شرائع واحکام خدائے تعالیٰ نے دنیا میں اس لئے نازل کئے کہ اپنی بڑی فصاحت و بلاغت اور
ایجادی قانونی طاقت اور چیستان طرازی کا فخر انسان پر ظاہر کرے اور یوں پہلے ہی سے اپنی جگہ
ٹھان رکھا تھا کہ کہاں بیہودہ ضعیف انسان؟ اور کہاں کا ان حکموں پر عمل درآمد؟ خدا تعالیٰ
اس سے برتر اور پاک ہے کہ ایسا لغو فعل کرے.رپورٹ جلسہ سالانہ 1897 صفحہ 70،69)
شرائط پر پابند ہونا باعتبار استطاعت ہے.لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا.( مکتوبات احمد جلد دوم صفحہ 81 مکتوب 49 بنام حضرت خلیفہ امسیح الاول )
ہم قرآن شریف ہی کی تعلیم دینے کو آئے ہیں.خدا تعالیٰ نے قرآن شریف تو اس
لئے بھیجا ہے کہ اس پر عمل کیا جاوے اس میں کہیں نہیں لکھا کہ خدا کسی کو مجبور کرتا ہے.الحکم جلد 5 نمبر 29 مورخہ 10 را گست 1901 ، صفحہ 7)
قابلیت فراست سے ظاہر ہوتی ہے.خدا نے کچھ چھپایا ہے اور کچھ ظاہر کیا ہے.اگر
بالکل ظاہر کرتا تو ایمان کا ثواب جاتا رہتا اور اگر بالکل چھپاتا تو سارے مذاہب تاریکی میں
دبے رہتے اور کوئی بات قابل اطمینان نہ ہوسکتی اور آج کوئی مذہب والا دوسرے کو نہ کہہ سکتا
کہ توغلطی پر ہے.اور نہ مواخذہ کا اصول قائم رہ سکتا تھا کیونکہ یہ تکلیف مالائیطاق تھی.مگر خدا
تعالیٰ نے فرمایا ہے : لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا
الحکم جلد 6 نمبر 9 مورخہ 10 / مارچ 1902 ، صفحہ 5)
جو نبی آتا ہے اس کی نبوت اور وحی و الہام کے سمجھنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کی
فطرت میں ایک ودیعت رکھی ہوئی ہے اور وہ ودیعت خواب ہے اگر کسی کو کوئی خواب سچی
کبھی نہ آئی ہو تو وہ کیوں کر مان سکتا ہے کہ الہام اور وحی بھی کوئی چیز ہے؟ اور چونکہ خدا تعالیٰ
کی یہ صفت ہے کہ لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا.اس لئے یہ مادہ اُس نے سب میں رکھ
دیا ہے.الحکم جلد 6 نمبر 31 مؤرخہ 31 اگست 1902 صفحه 6)
403
Page 412
شریعت کا مدار نرمی پر ہے سختی پر نہیں ہے : لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا
الحکم جلد 6 نمبر 37 مورخہ 17 / اکتوبر 1902 ، صفحہ 8)
حواس باطنی میں جس طرح اس وقت فرق آ جاتا ہے، حواس ظاہری میں بھی معمر ہو کر
بہت کچھ فتور پیدا ہو جاتا ہے.بعض اندھے ہو جاتے ہیں بہرہ ہو جاتے ہیں چلنے پھرنے سے
عاری ہو جاتے ہیں اور قسم قسم کی مصیبتوں اور دکھوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں.غرض یہ زمانہ بھی بڑا
ہی رڈی زمانہ ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہی زمانہ ہے جو ان دونوں کے بیچ کا زمانہ
ہے.یعنی شباب کا جب انسان کوئی کام کر سکتا ہے کیونکہ اس وقت قویٰ میں نشو ونما ہوتا ہے اور
طاقتیں آتی ہیں.لیکن یہی زمانہ ہے جبکہ نفس آتارہ ساتھ ہوتا ہے اور وہ اس پر مختلف رنگوں میں
حملے کرتا ہے اور اپنے زیر اثر رکھنا چاہتا ہے.یہی زمانہ ہے جو مؤاخذہ کا زمانہ ہے.اور
خاتمہ بالخیر کے لئے کچھ کرنے کے دن بھی یہی ہیں لیکن ایسی آفتوں میں گھرا ہوا ہے کہ اگر
بڑی سعی نہ کی جاوے تو یہی زمانہ ہے جو جہنم میں لے جائے گا اور شقی بنادے گا.ہاں ! اگر عمدگی
اور ہوشیاری اور پوری احتیاط کے ساتھ اس زمانہ کو بسر کیا جاوے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے
امید ہے کہ خاتمہ بالخیر ہو جاوے کیونکہ ابتدائی زمانہ تو بے خبری اور غفلت کا زمانہ ہے اللہ تعالیٰ
اس کا مواخذہ نہ کرے گا جیسا کہ خود اس نے فرمایا: لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا -
الحکم جلد 9 نمبر 1 مورخہ 10 جنوری 1905 ، صفحہ 3)
قرآن شریف میں لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا آیا ہے اور رہبانیت اسلام میں
نہیں ہے.جس میں پڑ کر انسان اپنا ہاتھ سکھا لے یا اپنی دوسری قوتوں کو بیکار چھوڑ دے یا اور
قسم قسم کی تکالیف شدیدہ میں اپنی جان کو ڈالے.عبادت کے لئے دکھ اٹھانے سے ہمیشہ یہ
مراد ہوتی ہے کہ انسان ان کاموں سے رُکے جو عبادت کی لذت کو دُور کرنے والے ہیں.اور
ان سے رُکنے میں اولاً ایسی ضرور تکلیف محسوس ہوگی اور خدا تعالیٰ کی نارضامندیوں سے پر ہیز
کرے.مثلاً ایک چور ہے اس کو ضروری ہے کہ وہ چوری چھوڑے، بدکار ہے تو بدکاری اور
بدنظری چھوڑے.اسی طرح نشوں کا عادی ہے تو اُن سے پر ہیز کرے.اب جب وہ اپنی
404
Page 413
محبوب اشیاء کو ترک کرے گا تو ضروری ہے کہ اوّل اوّل سخت تکلیف اٹھاوے مگر رفتہ رفتہ اگر
استقلال سے وہ اس پر قائم رہے گا تو دیکھ لے گا کہ ان بدیوں کے چھوڑنے میں جو تکلیف اس
کو محسوس ہوتی ہے وہ تکلیف اب ایک لذت کا رنگ اختیار کرتی جاتی ہے.کیونکہ ان بدیوں
کے بالمقابل نیکیاں آتی جائیں گی اور ان کے نیک نتائج جو سکھ دینے والے ہیں وہ بھی ساتھ ہی
آئیں گے.یہاں تک کہ وہ اپنے ہر قول و فعل میں جب خدا تعالیٰ ہی کی رضا کو مقدم کرلے گا
اور اس کی ہر حرکت و سکون اللہ ہی کے امر کے نیچے ہوگی تو صاف اور بین طور پر وہ دیکھے گا کہ
پورے اطمینان اور سکینت کا مزہ لے رہا ہے.یہ وہ حالت ہوتی ہے جب کہا جاتا ہے کہ
لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (البقرة 36) اسی مقام پر اللہ تعالیٰ کی ولایت میں آتا ہے
اور ظلمات سے نکل کر نور کی طرف آ جاتا ہے.یا درکھو! کہ جب انسان خدا تعالیٰ کے لئے اپنی محبوب چیزوں کو جو خدا کی نظر میں مکروہ اور
اس کے منشاء کے مخالف ہوتی ہیں چھوڑ کر اپنے آپ کو تکالیف میں ڈالتا ہے تو ایسی تکالیف
اٹھانے والے جسم کا اثر روح پر بھی پڑتا ہے اور وہ بھی اس سے متأثر ہو کر ساتھ ہی ساتھ اپنی
تبدیلی میں لگتی ہے یہاں تک کہ کامل نیازمندی کے ساتھ آستانہ الوہیت پر بے اختیار ہو کر گر
پڑتی ہے، یہ طریق ہے عبادت میں لذت حاصل کرنے کا.الحكم جلد 7 نمبر 9 مورخہ 10 مارچ 1903 ، صفحہ 1 - ملفوظات جلد دوم صفحہ 698)
لهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ اُس کے لئے جو اُس نے کام اچھے کئے اور اُس
پر جو اُس نے بُرے کام کئے.جنگ مقدس، روحانی خزائن جلد 6 صفحه (231)
رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى
الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا
انت مولينا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَفِرِينَ یعنی اے ہمارے خدا!! نیک باتوں کے نہ کرنے
405
Page 414
کی وجہ سے ہمیں مت پکڑ جن کو ہم بھول گئے اور بوجہ نسیان ادا نہ کر سکے اور نہ ان بد کاموں پر ہم
سے مؤاخذہ کر جن کا ارتکاب ہم نے عمداً نہیں کیا بلکہ سمجھ کی غلطی واقع ہو گئی اور ہم سے وہ بوجھ
مت اُٹھو جس کو ہم اُٹھا نہیں سکتے اور ہمیں معاف کر اور ہمارے گناہ بخش اور ہم پر رحم فرما.چشمه معرفت، روحانی خزائن جلد 23 صفحه 25)
لا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِہ جو امر فوق الطاقت اور نا قابل برداشت ہو جاوے اس
سے خدا بھی درگذر کرتا ہے.الحکم جلد 12 نمبر 22 مورخہ 26 /مارچ1908، صفحہ 4)
ماخوذ از تفسیر حضرت مسیح موعود علیہ السلام )
حضرت خلیفہ المسیح الاول رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:
يه سورة بقرۃ کا خاتمہ ہے.وہ بات جو میں نے ابتدا میں بیان کی تھی اس کا اس میں بھی پتہ
لگتا ہے کہ اصل غرض اِس سورۃ کریمہ کی اعلانِ جہاد ہے چنانچہ فَانصُرْنَا عَلَى
الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ.(البقرہ 287 ) میں اس مطلب کو ظاہر کر کے ختم کر دیا.فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ : مَنْ میں عموم ضروری نہیں.معرفہ بھی ہوتا ہے.یہاں بتا دیا ہے کہ
مغفرت ان کو ہوگی جو يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ ( البقرۃ5) کے مصداق ہیں.کیونکہ وہی
مُفْلِحُون ہیں.اور عذاب ان کو ہوگا جو اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ
تُنذِرُهُمُ (البقرة 7) کے مورد ہیں.ضمیمه اخبار بدر قادیان 20 رمئی 1909ء)
غُفْرَانَكَ رَبَّنا انسان جزع فزع میں بے صبری سے شہوت و حرص کے سبب حضرت حق
سُبحانہ کے فیضان سے رُک جاتا ہے.اس واسطے استغفار کا حکم دیا.تمام لوگوں پر ایک وقت
قبض و کسل کا آتا ہے اس کے دُور کرنے کے لئے یہ حکمی علاج ہے.فقہاء آئمہ میں سے ایک
امام کا یہ مذہب ہے جو مجھے بھی پسند ہے کہ اللهُم إِنِّي أَعُوذُبِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسْلِ کی دُعا
406
Page 415
واجب ہے.آجکل مسلمان یا تو عجز میں گفتار ہیں یا کسل میں.عجز کہتے ہیں اسباب مہیا نہ کرنے
کو اور گنل کہتے ہیں اسباب مہیا شدہ سے کام نہ لینے کو.ان کو چاہئے کہ وہ گنل چھوڑ دیں جس
کے اسباب میں سے ایک کبر وغرور خود پسندی بھی ہے.(ضمیمه اخبار بدر قادیان 20 رمئی 1909ء)
ہمارا رسول اور دوسرے مومن تو اس طریق پر چلتے ہیں کہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں.فرشتوں
کی نیک تحریکیں مانتے ہیں اور ان میں تفرقہ نہیں کرتے.یعنی یوں نہیں کہ کسی کو مان لیا اور کسی کو
نہ مانا.پھر ان کی گفتار، ان کے کردار سے کیا نکلتا ہے (قَالُوا کے معنے.بتایا.زبان سے یا اپنے
کاموں سے ) سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا یعنی ثابت کرتے ہیں کہ نہ صرف وہ اپنی زبان بلکہ اپنے اعمال سے
دکھاتے ہیں کہ باتیں سنیں اور ہم فرمانبردار ہیں.تیری مغفرت طلب کرتے ہیں.تیرے حضور
ہم نے جانا ہے.اے مولا! تو ہی ہمیں طاقت عطا فرما اور ہمارے نسیان و خطا کا مواخذہ نہ کر.ہم پر
وہ بوجھ نہ رکھ جو ہم سے برداشت نہ ہو سکیں.یہ دعا مومنوں کی ہے تم بھی مانگا کرو اللہ تعالیٰ قبول
فرمائے گا.ہر وقت جناب الہی سے مغفرت طلب کرتے رہو اور اسی کو اپنا والی و ناصر جانو.بعض
آدمی ایسے ہیں کہ ان کو سمجھانے والے کے سمجھانے کی برداشت نہیں.وہ اپنے خیالات کے اندر
ایسے منہمک ہوتے ہیں کہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے.اس قسم کی بے پرواہی اور تکبر کا نتیجہ ہے کہ
کفار نے تمہاری سلطنتیں لے لیں.اگر تم پورے طور سے خدا کی بادشاہت اپنے او پر مان لیتے اور
مومن بنتے تو کفار کے قبضہ میں نہ آتے.اللہ بڑا بے پرواہ ہے.اسے فرمانبرداری پسند ہے.خدا
تعالی آسودگی بخشے تو متکبر نہ بنو.لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ دوسروں کی بیٹیوں کے ساتھ نیک سلوک
نہیں کرتے حالانکہ ان کے اپنے گھر بیٹیاں ہیں جو دوسرے گھروں میں جانے والی ہیں.جو سلوک
تم نہیں چاہتے کہ ہم سے ہو وہ غیروں سے کیوں کرو ؟ اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہو اور خدا کے
فرمانبردار بننے کی کوشش کرو.اللہ تمہیں توفیق بخشے.الفضل 25 جون 1913 ، صفحہ 15)
407
Page 416
لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا: عیسائی کہتے ہیں کہ شریعت کا نزول ہمارے عجز کے
ثبوت کے لئے ہے.ایسے ہی کئی اور لوگ ہیں جن کا یہ عقیدہ ہے کہ شریعت پر عمل ناممکن
ہے.اس لئے فرمایا کہ ہم کوئی حکم ایسا نہیں دیتے جو انسان کی مقدرت، وسعت ، استطاعت
کے مطابق نہ ہو.ا لَهَا مَا كَسَبَتْ : جو کچھ عمل کرے اس کا فائدہ بھی اسی عامل کے لئے ہے.وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ : ہر مصیبت کی جڑ انسان کی نافرمانی ہوتی ہے.مَا أَصَابَكُمْ
مِنْ مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم (الشوری (31) پھر بھی بعض گستاخ لوگ اپنے دُکھوں کو
خدا کے ذمہ لگاتے ہیں.ربَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا: حدیث میں آیا ہے اس دعا کا نتیجہ تھا کہ نسیان پر مواخذہ نہیں ہوتا.خطا کی مثال یہ ہے کہ بندوق ماریں ہرنی کو اور لگ جائے انسان کو.ما اخرا إحتر کیا چیز ہے؟ اختر کے معنے غفلت کرنے کی وجہ سے کئی انسان شریر ہو
گئے.پھر اسی اختر کے معنے نہ سمجھنے سے تقدیر کے مسئلے میں غلطی لگی.اختر کے معنے ہیں ایسے
فعل کا ارتکاب جس کے بعد انسان سُست و کاہل ہو جائے.اختر کہتے ہیں گرد ڈالنے کو.حبش
الشئ اختر نام ہے ایسے عہد کا جس کے توڑنے سے انسان خیرات کے قابل نہیں رہتا.پس
اس کے معنے یہ ہوئے کہ اے ہمارے مولا کریم ! ہم کو ایسے افعال کا مرتکب نہ کر جن کا یہ نتیجہ ہو
کہ ہم تیرے حضور سے دھتکارے جائیں.جیسے کہ پہلے لوگوں نے بدذاتیاں کیں.معاہدات کا
نقض کیا اور مغضوب علیہم بنے.ہم نہ بنیں.نہ
انت مؤلينا : مولیٰ جب خدا کے لئے بولا جاوے تو اس کے تین معنے ہیں.1 - مالک.2.ربّ.3.ناصر.ضمیمه اخبار بدر قادیان 20 مئی 1909ء)
(ماخوذ از حقائق الفرقان)
408
Page 417
حضرت خلیفہ المسیح الثانی فرماتے ہیں :
وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ الله کے متعلق بعض لوگوں کا
خیال ہے کہ اسے لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا.والی آیت نے منسوخ کر دیا ہے.یعنی
پہلے تو یہ کہا گیا تھا کہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اگر تم اسے ظاہر کر یعنی اس کے مطابق عمل
کرو تب بھی اور اگر تم اس کو چھپاؤ یعنی صرف دل کے خیالات تک ہی محدود رکھو تمہارے
جوارح اس کے مطابق کوئی عمل نہ کریں تب بھی اللہ تعالیٰ اس کے متعلق تم سے حساب لے گا.لیکن پھر کہہ دیا کہ اللہ تعالی کسی شخص پر ایسا بوجھ نہیں ڈالتا جو اس کی طاقت سے باہر ہو.اور
چونکہ دل کے خیالات کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہوتے اس لیے وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي
انْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ الله والی آیت منسوخ ہوگئی.مگر ان کا یہ خیال درست
نہیں.اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نسخ حالات کے تغیر کے ساتھ تعلق رکھتا ہے ، نہ کہ دل کے
خیالات کے ساتھ.مثلاً اسلام میں پہلے گدھے کا گوشت کھانے کی اجازت تھی مگر بعد میں اس
سے روک دیا گیا.لیکن صحابہ کے دل کی حالت تو پہلے بھی ویسی ہی تھی جیسے بعد میں تھی.یعنی جس
طرح پہلے وہ اپنے دل کے خیالات پر قابو نہیں رکھتے تھے اسی طرح بعد میں بھی نہیں رکھتے تھے.پس دل کے خیالات کے متعلق نسخ کے کوئی معنے ہی نہیں ہیں.منسوخ تو وہ احکام ہوتے ہیں
جو تبدیلی حالات کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں.اور یہ امر تو تبدیلی پذیر ہے ہی نہیں.اصل بات یہ ہے کہ لوگوں نے اس آیت کو سمجھا ہی نہیں.انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ انسان
کے دل میں جو خیال بھی آجائے اس کے حساب لینے کا اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے.حالانکہ
اس آیت میں ان امور کا ذکر ہے جن کو انسان اپنے نفس میں چھپا کر رکھتا ہے.آنی خیالات تو
بخشے جائیں گے.لیکن ایک غلط عقیدہ ، بغض، حسد اور محل وغیرہ کے خیالات سب دل میں ہی
ہوتے ہیں اگر اُن کو بھی بخش دیا جائے تو پھر ایمان کی حقیقت کیا رہ جاتی ہے.پس اس جگہ تُخْفُوهُ سے مراد حسد، کینہ اور بغض وغیرہ ہے جو دل میں رکھا جاتا ہے.اسی
409
Page 418
طرح اس سے ایسے خیالات مراد ہیں جن کو انسان اپنے دل میں قائم رکھتا ہے اور جن کو عمل
میں لانے کی نیت کر لیتا ہے.لیکن اگر ایک خیال آئے اور انسان اُسے اپنے دل سے فور انکال
دے تو یہ کوئی گناہ نہیں.بلکہ ایک نیکی ہے جس میں اُس نے حصہ لیا.پس محض دل کے خیالات
قابل مواخذہ نہیں جب تک کہ اُن پر عمل نہ کیا جائے یا اُن کو پختگی سے قائم نہ کر لیا جائے.چنانچہ حضرت ابوہریرہ سے صحیحین میں مروی ہے کہ رسول کریم علیہ نے فرمایا ان الله
تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسُهَا مَا لَمْ تَتَكَلَّمُ أَوْ تَعْجَلُ بِهِ.یعنی اللہ تعالیٰ نے میری
امت کے ان خیالات سے درگزر فرما دیا ہے جو اُن کے دلوں میں پیدا ہوتے رہتے ہیں.بشر طیکہ وہ ان کو زبان پر نہ لائیں اور نہ اُن پر جلدی سے عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں.پس اس آیت میں ان خیالات کا ذکر کیا گیا ہے جن کو انسان اپنے دل میں چھپا کر رکھتا
ہے.اور جن کے متعلق سکیمیں سوچنا شروع کر دیتا ہے.وقتی اور آنی خیالات کا اس میں کوئی
ذکر نہیں اور نہ ان پر کوئی گرفت ہے.ہاں غلط عقائد اور بغض اور حسد اور کینہ وغیرہ بھی اگر بغیر
تو بہ کے بخش دیئے جائیں تو پھر ایمان کی کوئی حقیقت ہی نہیں رہتی اس لیے اُن پر مواخذہ کیا
جائے گا.کیونکہ یہی تمام گناہوں کی جڑھ ہیں.اسی وجہ سے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا
ہے.لَا يُوا خِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُ كُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ
(بقرة 226) یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری قسموں میں سے لغو قسموں پر تم سے کوئی مؤاخذہ نہیں کرے گا
ہاں جو گناہ تمہارے دلوں نے بالا رادہ کمایا ہے اُس پر تم سے مؤاخذہ کرے گا.دوسری جگہ
فرماتا ہے.اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا (بني اسرائيل
(37) یعنی کان آنکھ اور دل سب کے متعلق انسان سے سوال کیا جائے گا.یعنی کان آنکھ کے
گناہوں کے علاوہ ان خیالات کا بھی جائزہ لیا جائے گا جو مستقل طور پر کسی انسان کے دل میں
پیدا ہوتے رہے.اسی طرح فرماتا ہے.اِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ
امَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (النور 20)
410
Page 419
یعنی وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ مومنوں میں بدی پھیل جائے ان کے لیے بڑا دردناک عذاب
مقدر ہے.اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی.اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے.اس
آیت میں بھی ان لوگوں کا کوئی عمل بیان نہیں کیا گیا بلکہ ان کے دل کی حالت بیان کر کے سزا
تجویز کی گئی ہے.پس وہ خیالات جن کو انسان اپنے دل میں قائم رکھے اور اُن کے متعلق سوچتا اور غور کرتا
رہے خواہ ان کو عمل میں نہ لا سکے قابل سزا ہیں.مگر وہ ناپاک خیالات جو دل میں آئیں اور انسان
بائیں طرف تھوک کر اور استغفار اور لاحول پڑھ کر اُن کو دل سے نکال دے اُن پر کوئی گرفت
نہیں.اسی طرح اوپر کے رکوع میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةً
وَمَنْ يَكْتُمُهَا فَإِنَّهُ ائِمُ قَلْبُهُ (بقره 284) یعنی تم سچی گواہی کو مت چھپاؤ اور یاد رکھو کہ جو
شخص سچی گواہی کو چھپاتا ہے وہ یقیناً ایسا ہے جس کا دل گناہگار ہے.صحیحین میں حضرت
رض
ابوہریرہ سے یہ حدیث بھی مروی ہے کہ اِذَا هَم عَبدِي بِسَيِّئَةٍ فَلَا تَكْتُبُوهَا عَلَيْهِ فَإِنْ
عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا سَيْئَةً وَإِذَا هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا فَاكْتُبُوهَا حَسَنَةً فَإِنْ عَمِلَهَا
فَاكْتُبُوا عَشْرًا.یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے ملائکہ کو یہ حکم دے دیا ہے کہ جب میرا بندہ کسی بدی کا
ارادہ کرے تو اسے مت لکھو.ہاں اگر اس ارادہ کے مطابق عمل بھی کرلے تو ایک بدی اس کے
نامہ اعمال میں درج کر دو.لیکن اگر وہ کسی نیکی کا ارادہ کرے اور اس پر عمل نہ کرے تو اس کی
ایک نیکی لکھو.اور اگر اُس نیکی پر عمل کرلے تو پھر دس نیکیاں لکھو.ان آیات اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانی خیالات تین قسم کے ہیں.اول وسوسہ یا
خیال اٹھا اور خود بخود چلا گیا.اس کا تو نہ ثواب ہے نہ عذاب.دوم.ایک بدعقیدہ دل میں پیدا
ہوا یا ایک بدکام کی تحریک دل میں پیدا ہوئی اور اُس نے اُس کورڈ کر دیا.چونکہ بدی کا مقابلہ
نیکی ہے اس کو ایک نیکی کا ثواب ملے گا.سوم.اگر اس نے اُس کو باہر نہ نکالا اور اپنا مال سمجھ کر
دل میں رکھ لیا تو اس کو ایک بدی کا گناہ ہوگا.411
Page 420
احادیث میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ سخت گھبرائے اور انہوں نے
رسول کریم علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول
اللہ ! ہم نماز اور روزہ اور جہاد اور
صدقہ وغیرہ کے احکام پر تو عمل کر سکتے ہیں مگر اس آیت میں تو ایک ایسا حکم نازل ہوا ہے جس پر
عمل کرنے کی ہم میں طاقت ہی نہیں.اس پر آنحضرت عالم نے فرمایا.آتُرِيدُونَ آن
تَقُولُوا كَمَا قَالَ أَهْلُ الْكِتَبِ مِنْ قَبْلِكُمْ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا بَلْ قُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا
غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ.فَلَمَّا اقْتَرَأَهَا الْقَوْمُ وَذَلَّتْ بِهَا الْسِنَتُهُمُ انْزَلَ اللهُ فِي
أَثَرِهَا امَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ (مسلم) یعنی کیا تم چاہتے ہو کہ تم
وہی کہو جو اہل کتاب نے تم سے پہلے کہا تھا کہ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا.تمہارا فرض تو یہ ہے کہ تم کہو
سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ.جب صحابہ نے اپنے دل کی گہرائیوں سے یہ
الفاظ کہے اور اللہ تعالیٰ کے حضور انہوں نے اپنی گردنیں جھکا دیں اور اس کی مغفرت اور رحم کے
طلبگار ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اظہارِ خوشنودی کے طور پر یہ آیت نازل ہوئی کہ امن
الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ.اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول کریم علی نے
کے ارشاد پر صحابہ کرام نے فوراً اپنی غلطی تسلیم کرلی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی.پھر یہ
آیت منسوخ کس طرح ہو سکتی ہے؟ نسخ تو کسی عمل کا ہوتا ہے اور یہاں کسی عمل کا ذکر نہیں.پس یہ بالکل غلط ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے.اصل بات یہ ہے کہ اس آیت میں تزکیۂ نفس کے لیے خیالات کی پاکیزگی بھی ضروری
قرار دی گئی ہے.بے شک خیالات
کو کلی طور پر پاک رکھنا تو ہر انسان کے لئے ناممکن ہے
لیکن اگر کوئی برا خیال پیدا ہو تو اُسے اپنے دل سے نکال دینا تو ہر انسان کے لئے ممکن ہے.مثلا اگر کسی شخص کے دل میں یہ خیال آئے کہ میں رشوت لوں تو وہ اس کے متعلق سوچنا اور مختلف
قسم کی تدابیر عمل میں لانا شروع نہ کر دے بلکہ جہاں تک ہو سکے اس خیال کو فوراً اپنے دل سے
نکالنے کی کوشش کرے ورنہ اس کا نقش مضبوط ہوتا چلا جائے گا.اور پھر اس خیال کا مٹانا
412
Page 421
سخت مشکل ہو جائے گا.اسی طرح اگر کوئی چلتے چلتے ہیں مال دیکھتا ہے اور اس کے دل میں یہ
خیال آتا ہے کہ میں اسے اُٹھالوں تو صرف اس خیال کے آنے پر اُس سے مواخذہ نہیں ہوگا.ہاں اگر اسی خیال کے آنے پر وہ سوچنا شروع کر دے کہ میں کس طرح اس مال کو اٹھاؤں اور
کس وقت اٹھاؤں تو اس کا یہ سوچنا اور تدبیریں کرنا قابل مؤاخذہ ہوگا.غرض وہ خیال جو دل میں گڑ جاتا ہے اور جس کو سوچنے میں انسان لگ جاتا ہے اور تدبیریں
شروع کر دیتا ہے اس کا محاسبہ ہوگا.ورنہ اگر کسی کو خیال آئے کہ میں چوری کروں.اور وہ
اُسے فوراً اپنے دل سے نکال دے تو وہ ایک نیکی کرتا ہے.اسی طرح اگر کسی کو قتل کرنے کا
خیال آئے لیکن وہ اسے اپنے دل سے نکال دے تو وہ نیکی کرنے والا سمجھا جائے گا.سزا کا مستحق
وہ اسی حالت میں ہوتا ہے جب وہ اس خیال پر قائم رہتا ہے.غرض تزکیۂ نفس کی بنیاد انسانی
قلب کی صفائی پر ہے.اور اس کی اہمیت رسول کریم علی شمالی نے ایک اور جگہ بھی بیان فرمائی
ہے.آپ فرماتے ہیں.اِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ
فسد الجسد كله الا وَهِيَ الْقَلْبُ یعنی انسان کے بدن میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے.جب وہ
تندرست ہوتا ہے تو سارا جسم تندرست ہوتا ہے.اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو سارا جسم بگڑ جاتا
ہے.پھر آپ نے فرمایا.غور کے ساتھ سنو کہ وہ گوشت کا ٹکڑا دل ہے.پس اسلام میں پاکیزگی اس کا نام نہیں کہ صرف زبان پر اچھی باتیں ہوں.یا اعمال تو اچھے
ہوں اور دل میں برائی ہو.بلکہ اسلام میں اصل پاکیزگی دل کی سمجھی جاتی ہے.جو انسان اپنے
دل کے لحاظ سے پاکیزہ نہیں وہ خدا تعالیٰ کے نزدیک ہرگز پاک نہیں.ایک شخص اگر قطعاً
کوئی گناہ نہ کرے.مگر اس کے دل میں گناہ اور برائی سے اُلفت ہو اور گناہ کے ذکر میں اسے
لذت محسوس ہو تو وہ نیک اور پاک نہیں کہلائے گا.جب تک کہ اس کے دل میں بھی یہ بات نہ
ہو کہ اسے گناہوں میں ملوث نہیں ہونا چاہئے.اسی طرح کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ عادت
کے ماتحت انہیں غصہ آجاتا ہے مگر گالی نہیں دیتے.لیکن ان کا دل کہہ رہا ہوتا ہے کہ فلاں
413
Page 422
انسان بڑا بدمعاش اور شریر ہے.ایسے لوگوں کے متعلق ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ پاکیزہ ہیں
بلکہ یہ کہیں گے کہ وہ اپنے گند کو چھپائے بیٹھے ہیں.پس اسلام میں پاکیزگی دل کی ہے.اعمال
اور زبان تو آلات اور ذرائع ہیں جن سے پاکیزگی ظاہر ہوتی ہے.اس لئے اللہ تعالیٰ نے یہاں
فرمایا ہے کہ دل کی حالت بھی محاسبہ کے نیچے آتی ہے.خواہ تم اپنے دل کی حالت کو چھپاؤ یا ظاہر
کرو.یہاں خدا تعالیٰ نے کیا عجیب نکتہ بیان فرمایا ہے کہ زبان اور اعمال تو دلی حالت کا
اظہار کرتے ہیں اصل چیز دل کی حالت ہے اور خدا تعالیٰ اس کا محاسبہ کرے گا.پس فرماتا
ہے کہ تم اپنی دلی حالت کو ظاہر کر دیا چھپاؤ یعنی تم گندے اعمال نہ کرو یا زبان سے ظاہر نہ کر ومگر
تمہارے دل میں گند ہے تو ضرور پکڑے جاؤ گے.يُحاسِبكُم به الله میں باء کے تین معنے ہو سکتے ہیں.(1) ایک معنی ذریعہ اور سبب
کے ہو سکتے ہیں.اس لحاظ سے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ تم سے حساب
لے گا.یعنی تمہارے اعمال کی بنیاد دل پر رکھی جائے گی.صرف ظاہری اعمال کو نہیں دیکھا
جائے گا بلکہ دل کی حالت کو بھی مدنظر رکھا جائے گا.اور تمہاری نیتوں کو بھی دیکھا جائے گا.جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اتما الاعمال بالنیات یعنی اعمال کا دارو مدار نیتوں پر ہوتا
ہے.پس اعمال کے ساتھ دل کی نیت کو بھی مد نظر رکھا جائے گا.(2) دوسرے معنے اس کے
فی کے ہو سکتے ہیں یعنی اس کے بارے میں.“ جیسا کہ ایک دوسری آیت میں آتا ہے کہ
لا يُؤَاخِذُ كُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي ايْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُ كُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ
(سورة بقرة 226) (3) تیسرے معنی اس کے علی کے ہو سکتے ہیں.یعنی اس جرم پر اللہ تعالیٰ
تم سے حساب لے گا.يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ میں بتایا کہ جیسی جیسی انسان کی نیت ہوئی ویسی
ہی اس کی جزا ہوگی.سزا کے مستحق سزا پائیں گے اور جو مغفرت کے مستحق ہوں گے اللہ تعالیٰ
انہیں اپنے دامن مغفرت میں لے لے گا.66
414
Page 423
سورۃ بقرہ کے شروع میں رسول کریم علی کے چار عظیم الشان کاموں کا ذکر کیا گیا
تھا.اوّل.تلاوت آیات.دوم تعلیم کتاب.سوم تعلیم حکمت.چہارم - تزکیۂ نفوس.آپ
کے ابتدائی تین کاموں پر اس سورۃ میں تفصیلاً روشنی ڈالی گئی ہے.اب صرف يُز ٹیم کے
وعدہ کا ایفاء باقی تھا.سو اس رکوع میں اس شق پر بھی روشنی ڈال دی.ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ
تزکیہ نفوس کا کام کسی انسان کے بس کا نہیں.آخر والدین سے زیادہ محبت کرنے والا اور کون
وجود ہوسکتا ہے مگر وہ بھی اپنی اولاد کا تزکیۂ نفس نہیں کر سکتے.تزکیہ میں دو باتیں ضروری ہوتی ہیں.اول ترک گناہ.دوم روحانیت میں ترقی.ترک گناہ
کے لحاظ سے فرمایا کہ ہم تم کو تعلیم دیتے ہیں کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی کی ہے اور آسمان وزمین اور
کائنات کا ذرذرہ سب اللہ تعالیٰ کے ماتحت ہے.پس جس چیز کے لینے کی وہ اجازت دے
صرف وہی تم لو اور جس سے منع کرے اُس سے رُک جاؤ.کیونکہ مالک کی اجازت کے بغیر کسی
چیز کو استعمال کرنے والا مستوجب سزا قرار پاتا ہے.دوسری شق روحانیت میں ترقی کرنا تھا.اس کے لئے فرمایا کہ سب کچھ ہمارا ہے.اور ہمارے ہی ذریعہ سے ہر قسم کی خیر و برکت مل
سکتی ہے.اس لئے جب تم ہمارے حکموں کی اطاعت کرو گے تو ہم تم کو اپنی مغفرت کے دامن
میں لے لیں گے.اور ہمارا قادرا نہ تصرف تمہیں ہمارے قرب میں پہنچا دے گا.أمَنَ الرَّسُولُ مَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللهِ وَ
مَلَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهِ.وَقَالُوا
سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ
اس آیت میں تزکیہ نفوس کی تکمیل کے لئے اللہ تعالیٰ پر اس کے ملائکہ پر اس کی
کتابوں پر اور اس کے تمام رسولوں پر ایمان لانا مومن کا شعار قرار دیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے
کہ جب تک عقیدہ اور عمل دونوں کی اصلاح نہ ہو انسان اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے میں
کامیاب نہیں ہو سکتا.مگر افسوس ہے کہ اتنی واضح آیت کے باوجود بعض لوگ یہ خیال کرتے
415
Page 424
ہیں کہ نجات کے لئے صرف اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آنا کافی ہے.اس کے رسولوں اور کتابوں
وغیرہ پر ایمان لانا ضروری نہیں.اسی قسم کے خیالات ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی کے بھی تھے.اور
انہی خیالات کی وجہ سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اُسے اخراج از جماعت کی
سزا دی اور بڑے زور سے تحریر فرمایا کہ یہ عقیدہ اسلام کے سراسر خلاف ہے.اسلام تمام
رسولوں پر اور بالخصوص محمد رسول اللہ علیم پر ایمان لانا نجات کے لئے ضروری قرار دیتا ہے.لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُّسُلِهِ میں اس طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ کسی ایک رسول کا
انکار بھی انسان کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا مورد بنا دیتا ہے.پس خواہ کوئی نبی تشریعی ہو یا
غیر تشریعی ، پہلے زمانہ میں آچکا ہو یا آئندہ زمانہ میں آئے ، ہر ایک کا ماننا ضروری ہے.بیشک مدارج کے لحاظ سے ان میں بڑا فرق ہے.جس مقام پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں
اُس مقام پر نہ موسیٰ علیہ السلام ہیں، نہ عیسیٰ علیہ السلام اور نہ کوئی اور نبی.مگر جہاں تک
نفس ایمان کا سوال ہے جس طرح محمد رسول اللہ صلی علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے اسی طرح
بغیر کسی فرق کے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء پر بھی ایمان لانا ضروری
ہے اور اس لحاظ سے انبیاء میں کسی قسم کی تفریق پیدا کرنا جائز نہیں.اسی طرح خدائی کلام پر عمل
کرنے کے لحاظ سے بھی انبیاء میں کسی قسم کا کوئی امتیاز کرنا جائز نہیں.بیشک اُن کے درجات
مختلف ہوں.لیکن اُن پر کلام نازل کرنے والا چونکہ ایک ہی ہے اس لئے یہ فرق کرنا کسی
صورت میں بھی جائز نہیں کہ مثلاً فلاں نبی چونکہ درجہ میں بڑا ہے اس لئے اس پر نازل ہونے
والے کلام کو تو ہم مانیں گے لیکن فلاں نبی چونکہ درجہ میں چھوٹا ہے اس لئے اس پر نازل ہونے
والے کلام کو ماننا ہمارے لئے ضروری نہیں.اس قسم کا احمقانہ فرق کرنا ایسا ہی ہے جیسے مثلاً
کوئی کہے کہ میرے افسر نے فلاں حکم چونکہ رجسٹری کے ذریعہ نہیں بھیجا بلکہ عام ڈاک میں
بھیجا ہے اس لئے میں نے اس
کی تعمیل نہیں کی.کیا جاہل سے جاہل شخص بھی اس قسم کا عذر
پیش کر سکتا ہے؟ اور کیا اسے تسلیم کرنے کے لئے کوئی تیار ہوسکتا ہے؟ اگر نہیں تو پھر خدائی
416
Page 425
کلام کے متعلق یہ فرق کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ہی
مومنوں کی یہ علامت بیان فرمائی ہے کہ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ
الْمَصِيرُ یعنی وہ احکام الہیہ کی اطاعت میں ایک ذراسی غفلت اور سستی بھی گوارا نہیں کرتے
بلکہ ادھر اللہ تعالیٰ کا حکم سنتے ہیں اور اُدھر کہتے ہیں سمعْنَا وَأَطَعْنَا ہمارے رب !ہم نے تیرا
حکم سن لیا اور ہم اس کے دل سے
فرمانبردار ہیں.ا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ غُفْرَانَكَ دراصل اِغْفِرُ غُفْرَانَكَ ہے.یعنی
غُفْرَانَكَ سے پہلے ایک فعل محذوف ہے.اور معنی اس کے یہ ہیں کہ اے ہمارے رب ! ہمیں
اپنی بخشش سے حصہ دے اور ہمیں معاف فرما.چونکہ گزشتہ آیات میں تزکیۂ نفس کی طرف خاص طور پر توجہ دلائی گئی تھی.اس لئے اللہ تعالی
نے بتایا کہ اب محمد رسول اللہ علیم کی قوت قدسیہ کے نتیجہ میں ایک ایسی جماعت پیدا ہوگئی
ہے جو سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ کہنے والی ہے اور جس کا سر خدا تعالیٰ
کے آستانہ پر ہر حالت میں جھکا رہتا ہے.لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالی کوئی ایسا حکم نہیں دیتا جس کی
بجا آوری کی انسان میں طاقت نہ ہو.یا اُس کی استعداد اور قابلیت سے بالا ہو.پس جبکہ اس کی
طرف سے ہمیشہ ایسے ہی احکام نازل ہوتے ہیں جن پر عمل انسانی مقدرت سے باہر نہیں ہوتا تو لازماً
سب ذمہ داری انسان پر ہی عائد ہوتی ہے اور انعامات الہیہ کا بھی وہی مستحق ٹھہرتا ہے اور عدم تعمیل
کی بنا پر سزا کا بھی وہی مستحق قرار پاتا ہے.اسی لئے آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ لَهَا مَا
كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ یعنی انسان اگر اچھا عمل کرے گا تو اس کا فائدہ بھی اسے ہی پہنچے گا
اور اگر بُرا کام کرے گا تو اس کا نقصان بھی اُسے ہی ہوگا.ضمناً اس آیت میں اس مضمون کی طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے کہ جو کام اس زمانہ میں
امت محمدیہ کے سپرد ہوا ہے وہ اس کی طاقت اور قابلیت کے عین مطابق ہے اور ایک دن وہ
417
Page 426
اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچا کر دنیا کو دکھا دے گی کہ وہ اس منصب کی سب سے زیادہ اہل تھی.اگر یہی کام پہلے کسی نبی کی امت کو کرنا پڑتا تو وہ اُسے
کبھی سرانجام نہ دے سکتی.(2) اس آیت میں اسلام کی اس فضیلت کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ اس کے تمام احکام میں
انسان
کی کمزوریوں اور ضروریات کو مدنظر رکھتے ہوئے ایسی لچک رکھی گئی ہے کہ ہر حالت میں
وہ اُن پر عمل کر سکتا ہے.مگر باقی مذاہب اپنی تعلیم میں یا تو افراط کی طرف چلے گئے ہیں یا تفریط
کی طرف اور اس طرح وہ اپنے حقیقی توازن کو کھو بیٹھے ہیں.اور قلوب پر ان کی حکومت جاتی
رہی ہے.صرف اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جو فطرتِ انسانی کے مطابق تعلیم دینے کی وجہ
سے انسان کے دل پر حکمرانی کر رہا ہے.(3) اس آیت میں اس طرف بھی اشارہ فرمایا ہے کہ جب تم کو تمام احکام تمہاری طاقت
اور قابلیت کے مطابق دیئے گئے ہیں اور تم پر کوئی نا قابل برداشت بوجھ نہیں ڈالا گیا تو اب تمہارا
فرض ہے کہ تم بھی دیانتداری کے ساتھ ان احکام پر ایسا عمل کرو جیسا کہ عمل کرنے کا حق ہے.(4) اس آیت میں کفارہ کا بھی رڈ کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ گناہوں سے بچنا انسانی
مقدرت سے بالا نہیں بلکہ ہر انسان کے اندر ایسی طاقت رکھی گئی ہے کہ وہ اگر گناہوں پر غالب
آنا چاہے تو آ سکتا ہے.پس اس کی نجات کے لئے کسی کفارہ کی ضرورت نہیں بلکہ انسان کو خود
اپنے فطری قومی کو ابھارنے اور اُن سے کام لینے کی ضرورت ہے.لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ میں بتایا کہ ہم نے یہ قانون مقرر کر دیا ہے کہ
اگر کوئی اچھا کام کرے گا تو اُسے اُس کا فائدہ پہنچے گا اور اگر کوئی برا کام کرے گا تو اُس کا نقصان
بھی اُسے ہی پہنچے گا.کسب اور اکتساب میں یہ فرق ہے کہ کسب کی نسبت اکتساب میں زیادہ محنت اور
مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے پس نیکی کے متعلق کسب اور بدی کے متعلق اکتساب کا لفظ
رکھ کر اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ نیکی ایک فطری چیز ہے جس پر عمل انسان کے لئے
418
Page 427
کوئی بوجھ نہیں ہوتا.لیکن بدی ایک غیر فطری چیز ہے جو اخلاقی قوتوں کو برمحل استعمال نہ
کرنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اس لئے اس کے مرتکب کو ایسے رستہ پر چلنا پڑتا ہے جو اس
کے لئے تکلیف اور اذیت کا باعث بنتا ہے.حمد پھر ان الفاظ میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ نیکی تو ہر حال میں قابلِ جزا ہے.لیکن بدیوں میں سے صرف اس بدی کی سزا ملے گی جس میں اکتساب کا رنگ پایا جائے گا.یعنی
قصداً اور ارادتاً اس کا ارتکاب کیا جائے گا.اس کے بعد تزکیۂ نفس کے لئے اللہ تعالیٰ مومنوں کو بعض خاص دعائیں سکھلاتا ہے کیونکہ
دعا ہی ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے انسان اللہ تعالیٰ کا چہرہ دیکھتا ہے اور دعا ہی ایک ایسا ذریعہ
ہے جس سے اس کی قدرتوں پر زندہ ایمان پیدا ہوتا ہے اور پھر وہ دعا جو اللہ تعالیٰ خود سکھائے
اس کی قبولیت میں تو کسی شبہ کی گنجائش ہی نہیں رہتی.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہمارے مومن بندے
ہمیشہ یہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا اے ہمارے ربّ! اگر
ہم کبھی بھول جائیں یا کوئی خطا ہم سے سرزد ہو جائے تو ہمیں سزا نہ دیجیو بلکہ ہم سے رحم اور عفو کا
سلوک کیجیو.بھول جانے کے معنی یہ ہیں کہ کوئی کام کرنا ضروری ہومگر نہ کیا جائے.اور خطا کے
یہ معنی ہیں کہ کام تو کیا جائے مگر غلط کیا جائے.بعض لوگ اس بحث میں پڑ گئے ہیں کہ نسیان اور
خطا دو ہم معنی لفظ یہاں کیوں لائے گئے ہیں.وہ یہ نہیں سمجھتے کہ دنیا میں تمام کام دو قسم کے
ہوتے ہیں.کوئی کام تو ایسے ہوتے ہیں جو کرنے ضروری ہوتے ہیں مگر انسان نہیں کرتا.اور
کوئی کام ایسے ہوتے ہیں جو انسان کرتا تو ہے مگر غلط طور پر کرتا ہے اور یہ دونوں ہی غلطیاں
ہوتی ہیں.نسیان کے معنی بھول جانے کے ہیں اور بھولنا کرنے کے متعلق ہوتا ہے، نہ کرنے
کے متعلق نہیں ہوتا.پس لا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا کے معنی یہ ہوئے کہ خدایا ایسا نہ ہو کہ جو کام ہمارے لئے کرنے
ضروری ہیں وہ ہم نہ کریں اور اس طرح ہم ترقی سے محروم ہو جائیں.پس تو ہماری حفاظت فرما.419
Page 428
اور ہمیں اس غلطی سے محفوظ رکھ.أَو أخطأنا اور یا الہی یہ بھی نہ ہو کہ جو کام ہمیں نہیں کرنا چاہئے وہ
ہم کرلیں.یا ہم کریں تو وہی جو ہمیں کرنا چاہئے مگر غلط طریق پر کریں.پس نسیان اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جو کام کرنے تھے وہ انسان سے رہ جائیں اور خطا
کا لفظ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جو کام نہیں کرنے چاہئے تھے وہ کر لئے جائیں.یا جن
کاموں کا کرنا ضروری تھا وہ غلط طور پر کئے جائیں.غرض نسیان عدم عمل کا نام ہے اور خطا عمل کی خرابی کو کہتے ہیں.اسی لئے یہاں دو لفظ
استعمال کئے گئے ہیں.پس اس میں سے کوئی لفظ بھی زائد نہیں بلکہ ہر لفظ اپنی اپنی جگہ ضروری
ہے.نسیان کی مثال ایسی ہی ہے جیسے آدم علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ
فَنَسِي وَلَمْ نَجِدُ لَهُ عَزما (طه 116) یعنی آدم بھول گیا لیکن ہم نے بھی دیکھ لیا کہ اس کے دل
میں ہمارا حکم توڑنے کے متعلق کوئی ارادہ نہ تھا.پھر فرماتا ہے رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا یعنی مومن
یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اے خدا ہم پر اس طرح ذمہ داری نہ ڈالیو جس طرح تو نے اُن لوگوں پر
جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں ڈالی تھی.اختر کے ایک معنی چونکہ گناہ کے ہیں اس لئے اس دعا کا
ایک مفہوم یہ ہے کہ اے خدا! تو ہم پر اس طرح گناہ نہ ڈال جس طرح تو نے پہلی قوموں پر
ڈالا.یعنی ہمیں اُن اعمال سے اپنے فضل سے محفوظ رکھ جن کے نتیجہ میں ہماری طرف گناہ منسوب
ہوں.اور دنیا میں ہمیں ظالم اور روسیاہ قرار دیا جائے اور طرح طرح کے عیوب ہماری طرف
منسوب کئے جائیں جیسا کہ پہلی قوموں کے ساتھ ہوا.اضر کے دوسرے معنی عھد کے ہیں اس لحاظ سے لَا تَحْمِلُ عَلَيْنَا إِصْرًا کے معنی یہ
ہیں کہ الہی ہم سے کوئی ایسا عہد نے لیجیئو جس کو توڑ کر ہم تیری سزا کے مستوجب ہوں جس طرح
پہلی قومیں سزا کی مستوجب ہوئیں.یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر عہد لینا بُری چیز تھی تو پھر دوسری امتوں سے کیوں لئے
420
Page 429
گئے؟ اور اگر اچھی چیز ہے تو اس اُمت سے کیوں نہ لیا جائے ؟ بلکہ اس کے کامل امت ہونے
کی وجہ سے تو ضروری ہے کہ اس کے ہر فرد سے عہد لیا جائے.سو یا د رکھنا چاہیے کہ لا تخیل
عَلَيْنَا إِخترا کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ ہم سے کوئی عہد ہی نہ لیا جائے.بلکہ مطلب یہ ہے کہ
اے ہمارے رب ! آپ ہم سے جو عہد لیں اُس کے متعلق ہمیں توفیق بھی عطا فرمائیں کہ ہم اس
کے مطابق عمل کریں اور پہلی قوموں کی طرح عہد شکن اور غذار قرار نہ پائیں.گویا یہ دعا عہد
سے بچنے کے لئے نہیں بلکہ عہد کی ذمہ داریوں پر باحسن طریق عمل پیرا ہونے کے لئے ہے.(3) اضر کے ایک معنے بوجھ کے بھی ہیں.اس لحاظ سے اس کے معنے یہ ہیں کہ اے
ہمارے رب ! تو ہم پر کوئی ایسا بوجھ نہ ڈال جیسا کہ تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر بوجھ ڈالا.اس
کے یہ معنے نہیں کہ ہمیں اتنی نمازیں پڑھنے کو نہ بتا کہ جو ہم پڑھ نہ سکیں کیونکہ خدا تعالیٰ پہلے ہی
فرما چکا ہے کہ لا يُكَلِّفُ
اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا.خدا تعالیٰ کی طرف سے جو حکم آتے ہیں وہ
انسان کی طاقت اور اُس کی توفیق کے مطابق ہوتے ہیں.پس اس کے یہ معنی نہیں بلکہ اس
کے معنی یہ ہیں کہ بعض جرائم کی بنا پر پہلے لوگوں کے لئے جو سزائیں نازل کی گئی تھیں وہ سزائیں
ہم پر نازل نہ ہوں اور ہم سے وہ غلطیاں سرزد نہ ہوں جو پہلے لوگوں سے سرزد ہوئیں اور جن کی وجہ
سے وہ تباہ کر دیئے گئے.انہوں نے تیری نافرمانیاں کیں اور تیرے احکام کے خلاف انہوں
نے قدم اٹھایا جس کی وجہ سے اُن پر ایسی حکومتیں مسلط ہوئیں اور ایسے قوانین اُن کے لئے
مقرر کر دئیے گئے جو ان کے لئے ناقابل برداشت تھے.تو ہمیں اپنے فضل سے ایسے مقام پر
کھڑا کیجیو کہ ہم سے ایسی خطائیں سرزد نہ ہوں اور ہمیں ایسی سزائیں نہ ملیں جو ہمارے نفس کی
طاقت برداشت سے باہر ہوں.اس کے یہ معنی نہیں کہ نفس کی طاقت برداشت کے مطابق
اگر خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی سزا ملے تو اس میں کوئی حرج نہیں.اصل بات یہ ہے کہ ہر
روحانی سزا انسان کی برداشت سے باہر ہوتی ہے.یہ انسان کی رذالت ہی ہوتی ہے جس کی
وجہ سے وہ ایسی سزا کو برداشت کر لیتا ہے ورنہ اگر شرافت نفس ہو تو چھوٹی سے چھوٹی سزا بھی
421
Page 430
انسان کے لئے ناقابل برداشت ہوتی ہے.چنانچہ دیکھ لو جب کسی کو دوسرے سے محبت ہوتی
ہے تو اس کی معمولی سے ناراضگی کو دیکھ کر ہی اس کا دل بے چین ہو جاتا ہے.بعض دفعہ کہتا
ہے اُس نے مجھ سے اچھی طرح باتیں نہیں کیں.بعض دفعہ کہتا ہے اُس نے مجھ سے باتیں تو
کیں مگر اُن میں بشاشت معلوم نہیں ہوتی تھی اور اس بات کا اُس کی طبیعت پر اتنا بوجھ پڑتا ہے
کہ وہ عمگین ہو جاتا ہے.پس اس سے یہ مراد نہیں کہ ہمیں بڑی سزا نہ دیجیو چھوٹی سزاد یجیو بلکہ
مطلب یہ ہے کہ ہمیں کوئی سزاد یحیٹو ہی نہیں نہ چھوٹی نہ بڑی.پھر دنیا میں بعض مصائب ایسے بھی ہوتے ہیں جو بغیر قصور کے آ جاتے ہیں.قصور ہمسایہ کا
ہوتا ہے اور دکھ اُسے پہنچ جاتا ہے.قصور دوست کا ہوتا ہے اور سزا کا اثر اس پر آپڑتا ہے.اس
لئے جہاں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو یہ دعا سکھلائی کہ تم یہ کہا کرو کہ ہم سے ایسی خطا یا نسیان نہ ہو
جائے جس کی وجہ سے ہم تیری سزا کے مستحق ہو جائیں.وہاں دوسری دعا یہ سکھلائی کہ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ.اے خدا ایسا نہ ہو کہ
قصور تو ہمارے ہمسایہ کا ہو اور سزا ہمیں مل جائے.یا قصور دنیا کا ہو اور اس کی مصیبت کا اثر ہم پر
آپڑے.مگر یہاں ایک شرط بڑھا دی اور وہ یہ ہے کہ مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ اِس شرط کو اس لئے
بڑھایا گیا ہے کہ یہاں ناراضگی کا سوال نہیں بلکہ دنیوی مصائب اور ابتلاؤں کا ذکر ہے.ناراضگی بے شک چھوٹی بھی برداشت نہیں ہو سکتی مگر چھوٹی تکلیف برداشت کر لی جاتی ہے.پس جہاں روحانی سزا اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ذکر تھا وہاں تو یہ دعا سکھلائی کہ ہم میں تیری کسی
ناراضگی کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں وہ ناراضگی چھوٹی ہو یا بڑی.مگر جب دنیوی تکالیف کا
ذکر آیا تو یہ دعا سکھلائی کہ چھوٹے موٹے ابتلاؤں پر مجھے اعتراض نہیں.میں یہ نہیں کہتا کہ
میرا قدم ہمیشہ پھولوں کی سیج پر رہے.البتہ وہ ابتلاء جو تیری ناراضگی کا موجب نہیں اور جودنیا میں
عام طور پر آیا ہی کرتے ہیں اُس کے متعلق میری صرف اتنی درخواست ہے کہ کوئی ابتلاء ایسا نہ
ہو جو میری طاقت سے بالا ہو.یہ مطلب نہیں کہ مومن ایسے ابتلاء خود چاہتا ہے بلکہ خدا تعالیٰ
422
Page 431
نے چونکہ بتایا ہوا ہے کہ میں مومنوں کا امتحان لیا کرتا ہوں اس لئے مومن یہ نہیں کہتا کہ خدایا
میرا امتحان نہ لے بلکہ وہ کہتا ہے خدا یا امتحان تو لیجیومگر ایسانہ لیجیو کہ میری طاقت سے بڑھ کر ہو.غرض جو حصہ ناراضگی کا تھا وہاں تو کہہ دیا کہ میں ذراسی ناراضگی بھی برداشت نہیں کر سکتا مگر
جہاں دنیوی تکالیف اور ابتلاؤں کا ذکر تھا وہاں کہہ دیا کہ خدایا ! تکالیف تو آئیں مگر ایسی نہ ہوں
جوہماری طاقت سے بڑھ کر ہوں.پھر فرمایا وَاعْفُ عَنَّا اے خدا ہم سے عفو کر.یہ نسینا کے مقابلہ میں ہے.یعنی جو کام
ہمیں کرنے چاہئیں تھے چونکہ ہم نے نہیں کئے اس لئے ہمیں تو معاف فرمادے.وَاغْفِرْ لَنَا اور جو غلط کام ہم کر چکے ہیں اُن کے خمیازہ سے ہمیں بچالے اور ان کاموں کو
نہ کئے کی طرح کر دے.عفو کے معنی رحم کے بھی ہوتے ہیں اور جو چیز کسی انسان سے رہ جائے
اس کا ازالہ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ وہ مہیا کر دی جائے.اس لئے وَاعْفُ عَنَّا کے یہ بھی معنی
ہیں کہ جو چیز رہ گئی ہے اُس کو تو اپنے فضل اور رحم سے ہمیں مہیا فرما دے.اس کے مقابلہ میں
جو کام غلط ہو جائے اس کی درستی اسی طرح ہو سکتی ہے کہ اس کو مٹا دیا جائے.چنانچہ اخطانا
کے مقابلہ میں اغفر لنا رکھ دیا.اور غفر کے معنی عربی زبان میں مٹا دینے کے ہی ہوتے
ہیں.پس اس کے معنی یہ ہیں کہ اے خدا جو کام ہم غلط طور پر کر چکے ہیں اُن کو مٹادے اور انہیں
نہ کئے کی طرح کر دے.گویا ایک طرف تو یہ کہ دیا کہ جو کام ہم نے نہیں کیا اور اس طرح رخنہ
واقع ہو گیا ہے اس رخنہ کو تو اپنے فضل سے پُر کر دے اور دوسری طرف یہ کہہ دیا کہ جو کام ہم
غلط طور پر کر چکے ہیں اُن کو تو مٹا ڈال.وارحمنا پھر اس کام کے نتیجہ میں ہم سے جو اور غلطیاں ہوئی ہیں اور جن ترقیات کے حصول
میں روک واقع ہو گئی ہے ان غلطیوں کے متعلق بھی ہم پر رحم فرما.اور ہماری ترقیات کے راستہ
میں جو روکیں حائل ہو گئی ہیں اُن کو اپنے فضل سے دُور کر دے.أَنتَ مَوْلنا تو ہمارا مولیٰ ہمارا آقا اور ہمارا مالک ہے.آخر ہماری کمزوریاں کسی نہ کسی
423
Page 432
رنگ میں لوگوں نے تیری طرف ہی منسوب کرنی ہیں.لوگوں نے یہی کہنا ہے کہ یہ خدائی
جماعت کہلاتی تھی مگر اسے بھی دکھ پہنچا.اور اسے بھی دوسروں کی طرح تکلیف ہوئی.پس اے
ہمارے مولیٰ تو ہمارا آقا ہے اور ہم تیرے خادم ! تُو آ قا ہونے کے لحاظ سے ہم پر رحم کر کیونکہ
ہماری کمزوریاں آخر تیری طرف ہی منسوب ہوں گی اور لوگ ہدایت سے محروم ہو جائیں گے.احادیث میں آتا ہے کہ غزوہ اُحد میں جب ابو سفیان نے بڑے زور سے کہا کہ لَنا عُری و
لا عُرى لَكُمْ یعنی ہماری تائید میں ہمارا عرب ہی بہت ہے مگر تمہاری تائید میں کوئی بت نہیں.تو
اُس وقت رسول
کریم علیم نے مسلمانوں سے فرمایا کہ تم کہو.لَنَا مَوْلى وَلَا مَوْلى لَكُمْ.ہمارا
والی اور ہمارا مددگار ہمارا حتی وقیوم خدا ہے مگر تمہارا کوئی والی اور مددگار نہیں.یہ آنت
مولنا کی سچائی کا کیسا عملی ثبوت تھا کہ تلواروں کے سایہ میں بھی انہوں نے یہی کہا کہ اللہ
ہمیں بچا سکتا ہے.آخر میں یہ تعلیم دی کہ تم خدا تعالیٰ سے یہ دعا بھی کرتے رہو کہ فَانُصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ
یعنی اے خدا ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرما.ہم بے بس اور کمزور ہیں لیکن ہمارا دشمن طاقتور اور
تعداد میں بہت زیادہ ہے.ہمارا غلبہ صرف اسی صورت میں ہوسکتا ہے جبکہ تو ہمارے ساتھ ہو اور
اپنے رحم اور کرم سے کام لے کر ہمارے ایک ایک آدمی کے اندر ایسی روح پھونک دے کہ وہ سوسو
بلکہ ہزار ہزار مخالف پر بھی بھاری ہو.اگر تو اپنے فضل سے ایسے سامان پیدا فرما دے تو ہم بچ سکتے
ہیں ورنہ ہمارے بچاؤ کی اور کوئی صورت نہیں.پس اے ہمارے رب ! جولوگ ایسے کام کر رہے ہیں
جن سے اسلام کی ترقی میں روک واقع ہوتی ہے اُن پر تو ہمیں غالب کر اور ایسے سامان پیدا فرما جو
تیری تبلیغ اور تیرے نام کو دنیا میں پھیلانے کا باعث ہوں.پھر یہ دعا صرف مادی غلبہ کے لئے ہی نہیں بلکہ روحانی رنگ میں بھی دشمنوں پر غالب
آنے کے لئے ایک عاجزانہ پکار ہے اور اس میں خدا تعالیٰ کے حضور یہ عرضداشت پیش کی گئی
ہے کہ اے ہمارے رب ! اگر ہمارے اندر تیرے اس پاک رسول پر ایمان لانے کے نتیجہ میں
424
Page 433
کوئی تغیر پیدا نہ ہوا اور کفار میں اور ہم میں ایک نمایاں روحانی امتیاز اور فرق لوگوں کو محسوس نہ
ہوا.ہمارے اخلاق اور کردار اُن سے بلند نہ ہوئے اور ہمارے معاملات اُن سے بہتر نہ ہوئے
تو دنیا ہمیں طعنہ دے گی کہ انہوں نے محمد رسول اللہ صلیم کے ساتھ ہو کر کیا فائدہ اُٹھایا.ان
میں تو کوئی بھی تبدیلی پیدا نہ ہوئی.پس اے خدا تو اپنے فضل سے ہمیں اپنے اندر ایسا نیک تغیر
پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما کہ ہم تیرے رحم اور کرم کو جذب کرلیں اور کفار پر ہمیں جسمانی رنگ
میں ہی نہیں بلکہ اخلاق اور روحانیت کے لحاظ سے بھی ایک نمایاں تفوق اور غلبہ حاصل ہو
جائے اور تیرا دین دنیا کے کناروں تک پھیل جائے.(ماخوذ از تفسير كبير - سورة البقرة زير آيات 285 تا 287)
حضرت خلیفہ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز فرماتے ہیں:
لسان العرب میں ایک..حدیث بیان کی ہے کہ مَنْ قَرَأَ الْآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ
الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ أَى أَغْنَتَاهُ عَنْ قِيَامِ الَّيْلِ (لسان العرب.باب كفى - الجزء 15
صفحہ 226) جس نے رات کے وقت سورۃ البقرۃ کی آخری دو آیات پڑھیں تو وہ اس کے
لئے کافی ہوں گی یعنی وہ دونوں آیات رات کے قیام سے اسے مستغنی کردیں گی.بعض نے اس کے یہ معنی کئے ہیں کہ یہ دو آیات سب سے کم تعداد ہے جو رات کو قیام کے
وقت قراءت کے لئے کافی ہیں.اسی طرح بعض نے یہ معنی کئے ہیں کہ یہ دونوں آیات شرکے
مقابلے پر کافی ہیں اور مکروہات سے بچاتی ہیں.اگر ان پر غور کیا جائے اور ان آیات کے معانی ہر ایک پر واضح ہوں تو ان آیات میں بہت
ساری باتیں آجاتی ہیں.اس میں دعائیں بھی ہیں اور شر سے بچنے کے راستے بھی بتائے گئے ہیں
اور ایمان میں پختگی کے راستے بھی بتائے گئے ہیں.اس حدیث کے حوالے سے بعض سوال
اٹھ سکتے ہیں کیونکہ اس سے بعض دفعہ یہی معنی ظاہر ہوتے ہیں کہ پڑھ لیا تو کافی ہو گیا.اس لئے
اس وقت میں ان آیات کے حوالے سے کچھ وضاحت کروں گا.425
Page 434
سورۃ بقرہ کی آخری دو آیات میں سے پہلی آیت یہ ہے آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ
رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللهِ وَمَلَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهِ
وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ (البقرة 286)
اور آخری آیت یہ ہے کہ لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا
مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا
حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَابِهِ.وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْلَنَا
وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِين (البقرة 287)
ان آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی اس رسول پر اس کے رب کی طرف سے نازل کیا
گیا.اس پر وہ خود بھی ایمان رکھتا ہے اور مومن بھی ایمان رکھتے ہیں اور یہ سب اللہ اور اس کے
فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اس کے
رسولوں کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے.اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا حکم سن لیا
اور ہم دل سے اس کی اطاعت کرتے ہیں.اور ان کی یہ دعا ہے کہ اے ہمارے رب ! ہم تیری
بخشش طلب کرتے ہیں اور تیری طرف ہی ہمیں کوٹنا ہے.اور دوسری آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص پر اس کی طاقت سے بڑھ کر کوئی
ذمہ داری نہیں ڈالتا.جو اس نے اچھا کام کیا وہ اس کے لئے نفع مند ہو گا اور جو اس نے بُرا کام
کیا ہوگا وہ اس پر وبال بن کر پڑے گا.اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ! اگر ہم بھول
جائیں یا کوئی غلطی کر بیٹھیں تو ہمیں سزا نہ دینا اور اے ہمارے رب ! ہم پر اس طرح ذمہ داری نہ
ڈال جس طرح تو نے ان لوگوں پر ڈالی تھی جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں.اسی طرح اے ہمارے
رب ہم سے وہ بوجھ نہ اٹھوا جس کے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں.ہم سے درگزر کر.ہمیں
بخش دے.ہم پر رحم کر.تو ہمارا مولا ہے.پس کافروں کے گروہ کے خلاف ہماری مدد کر.توجیسا کہ اس ترجمہ سے واضح ہو گیا کہ کیوں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات رات
کو پڑھنے کو کافی قرار دیا.پہلی آیت میں تزکیہ نفس کی طرف توجہ دلاتے ہوئے یہ بتایا گیا
426
Page 435
ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ.اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ.اس کی کتابوں پر ایمان رکھو.اور اس
کے رسولوں پر ایمان رکھو.کیونکہ یہ ایمان میں کامل ہونے کا ذریعہ ہیں اور یہ ایمان صرف زبانی
اقرار نہیں ہے بلکہ عقیدے کے لحاظ سے بھی اور عمل کے لحاظ سے بھی ضروری ہے اور یہ بات
ہمیشہ پیش نظر رہنی چاہئے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان اُس وقت مضبوط ہوتا ہے جب تقویٰ میں ترقی کی
طرف قدم بڑھ رہے ہوں.اس کے فرشتوں پر ایمان اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ یقین ہو کہ
اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی ذمہ داریاں متروک نہیں ہو گئیں.بلکہ آج بھی وہ اپنے مفوّضہ فرائض
ادا کر رہے ہیں.اسی طرح پہلے انبیاء پر جو کتابیں اتریں وہ بھی یقیناً خدا تعالیٰ کی طرف سے تھیں.لیکن یہ اور
بات ہے کہ زمانے نے ان میں بگاڑ پیدا کر دیا.لیکن بہر حال وہ کتابیں ان رسولوں پر اللہ تعالیٰ
کی طرف سے اتری ہوئی کتابیں تھیں.خدا تعالیٰ نے ان کتابوں کی بھی ہر اچھی تعلیم قرآن
کریم میں محفوظ کر کے پہلی کتب کی تصدیق بھی کر دی اور قرآن کریم کی حفاظت کی ضمانت دے
کر آئندہ کے لئے اس شرعی کتاب کے تاقیامت ہر قسم کی تحریف سے پاک رہنے کا اعلان بھی
فرما دیا اور پھر تمام رسولوں پر ایمان کی طرف اس میں توجہ دلائی ہے.یہ اسلام کی خوبی ہے کہ تمام رسولوں کو مانے کا حکم ہے.یہاں یہ
نہیں کہا گیا کہ تمام سابقہ
رسولوں کو مانو بلکہ رسولوں پر ایمان ہے اور قرآن کریم اور آنحضرت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے مسیح موعود کے آنے کا بتایا اور جو راستہ کھول دیا تو یہ راستہ کھول کر آئندہ آنے والے رسولوں
کو ماننے اور ایمان لانے کا بھی اس میں حکم فرما دیا.اب یہ ان نام نہاد مسلمان علماء کی بدقسمتی
ہے جنہوں نے نہیں مانا کہ اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق مبعوث ہونے والے انبیاء کی
بعثت کے طریق کو چھوڑ کر اس طریق پر مسیح موعود کے نازل ہونے کا انتظار کر رہے ہیں جو
اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق نہیں ہے.قرآن پر ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود قرآن کی
اس بات کا رڈ کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ حضرت عیسی فوت ہو گئے
اور کوئی شخص جو اس دنیا میں آئے کبھی زندہ آسمان پر نہیں جاتا، بلکہ اس کی روح جاتی ہے.427
Page 436
اس دنیا میں آنے والی ہر چیز فانی ہے.اس آیت میں تو تمام رسولوں پر ایمان کی بات ہے.پھر یہ لوگ مسیح موعود کا انکار کر کے تمام رسولوں پر ایمان کی بھی نفی کر رہے ہیں.اور ساتھ ہی عام
مسلمانوں کو جن کا علم محدود ہے ان کو اپنے پیچھے لگا کر ان کے ایمان میں بھی رخنہ پیدا کر رہے
ہیں.پس اس حقیقت کو ان لوگوں کو سمجھنا چاہئے.حدیثیں بھی پڑھتے ہیں.قرآن بھی پڑھتے
ہیں.جہاں واضح طور پر ان باتوں کی طرف اشارہ ہے اور پھر بھی نہیں سمجھتے.تو ان کو اس
حقیقت کو سمجھنا چاہئے کہ جس طرح ہمیشہ انبیاء آئے ہیں اسی طرح مسیح موعود نے بھی آنا تھا.اگر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے خدا تعالیٰ کی طرف سے ہونے کا دعویٰ کیا ہے تو
اس کی دلیلیں بھی پیش کی ہیں.خدا تعالیٰ کی فعلی تائید بھی ان کے سچا ہونے کی شہادت دے رہی
ہے.اب ان لوگوں کو چاہئے کہ عقل کریں اور اس مسیح موعود کو مان کر مومنین کے گروہ میں
شامل ہوں.اس گروہ میں شامل ہوں جو سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا کہنے والے ہیں اور جنہوں نے سمعنا
وأطعنا پر عمل کیا وہی پھر غُفْرَانَكَ رَبَّنَا یعنی اے ہمارے رب ہم تیری بخشش طلب کرتے
ہیں، کی اس دعا کے بھی صحیح حقدار بنیں گے اور بنتے ہیں.اور اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے پر اللہ
تعالیٰ کی جنت کو حاصل کرنے والے بھی بنیں گے.یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے.اللہ تعالیٰ ہمارے
مسلمان بھائیوں کو بھی اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.اگلی آیت جو سورۃ البقرہ کی آخری آیت ہے.اس میں اللہ تعالیٰ نے شروع ہی اس بات
سے کیا ہے کہ لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا - یعنی اللہ تعالی کے احکامات انسانی وسعت کے
اندر ہیں.اللہ تعالیٰ ایسے احکام دیتا ہی نہیں جو انسانی طاقت سے باہر ہوں.لوگ کہتے ہیں جی
فلاں حکم بڑا مشکل ہے.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا کوئی حکم ایسا نہیں جو طاقت سے باہر ہو.حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ :
ہمیں حکم ہے کہ تمام احکام میں، اخلاق میں، عبادات میں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
پیروی کریں.پس اگر ہماری فطرت کو وہ قوتیں نہ دی جاتیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
تمام کمالات کو ظنی طور پر حاصل کر سکتیں تو یہ حکم ہمیں ہرگز نہ ہوتا کہ اس بزرگ نبی کی پیروی
428
Page 437
کرو.کیونکہ خدا تعالیٰ فوق الطاقت کوئی تکلیف نہیں دیتا.طاقت سے بڑھ کر کوئی تکلیف
نہیں دیتا.جیسا کہ وہ خود فرماتا ہے لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا.(حقیقۃ الوحی، روحانی خزائن جلد 22 ، صفحہ 156)
پس یہ جو فرمایا ہے کہ یہ آخری دو آیات کافی ہیں.یہ صرف پڑھ لینے سے نہیں.بلکہ پہلی
آیت میں ایمان پر مضبوط ہونے کا حکم ہے اور جب ایمان مضبوط ہو جائے تو وہ اس قسم کی
حرکت کر ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی کچھ باتوں کو تو مانے اور کچھ کو نہ مانے اور ر ڈ کردے.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اُسوہ تمہارے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قائم ہو گیا.اس لئے ایمان
کی انتہا ئیں حاصل کرنے کے لئے اس اُسوہ پر چلنے کے راستے تلاش کرو اور یہ
کبھی خیال نہ
آئے کہ بعض احکامات ہماری طاقت سے باہر ہیں.اللہ تعالیٰ نے مختلف حالتوں میں بعض
ایسی سہولتیں بھی دے دی ہیں.اسلام میں دین کے معاملے میں سب سے زیادہ سہولتیں ہیں.یہ
کہا ہی نہیں جا سکتا کہ بعض احکامات ہماری پہنچ سے باہر ہیں جن پر عمل نہیں ہوسکتا.اگر انسان
دین کے معاملہ میں ضرورت سے زیادہ سہل پسند نہ ہو تو کوئی حکم ایسا نہیں جو بوجھ لگ رہا ہو.اگر دنیاوی کاموں کے لئے انسان محنت اور کوشش کرتا ہے تو دین کے معاملے میں کیوں
محنت اور کوشش نہیں کر سکتا ؟
پس یہ واضح ہو کہ آخری دو آیات پڑھ لینے سے انسان تمام دوسرے احکامات سے آزاد
نہیں ہو جاتا بلکہ مطلب یہ ہے کہ جو غور کر کے پڑھے گا پھر وہ اس پر عمل بھی کرے گا.قیام اللیل سے انسان کس طرح مستغنی ہو سکتا ہے؟ جبکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا
نمونہ ہمارے سامنے پیش فرما دیا ہے اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ
آپ کا اُسوہ ہمارے لئے قابل تقلید اور پیروی کرنے کے لئے ہے.اگر اس کا کوئی مطلب ہو
سکتا ہے تو اتنا کہ ان آیات پر غور کرنے سے اللہ تعالیٰ کی مدد سے ایمان میں اتنی ترقی ہوگی کہ
عبادتوں کے لئے جاگنا اور توجہ دینا کوئی بوجھ نہیں لگے گا.بخاری میں اس حدیث کے الفاظ صرف اس قدر ہیں کہ مَنْ قَرَأَ بِالْايَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ
429
Page 438
الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَتاه - یعنی جس نے رات کے وقت سورۃ بقرہ کی دو آیات پڑھیں تو وہ
دونوں آیات اس کے لئے کافی ہوگئیں.(بخاری کتاب التفسير - باب فضل سورة البقرة)
اللہ تعالی کی پناہ میں آنے اور اس کا رحم اور بخشش مانگنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فضل فرمائے
گا تو پھر ایمان میں یہ ترقی ہوتی ہے جو کافی ہوتی ہے اور عبادات اور نیک اعمال کی طرف پھر
توجہ پیدا ہوگی.ورنہ اگر یہ خیال ہو کہ صرف آیات پڑھ لینا کافی ہے تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ
نے یہ فرمانے کے بعد کہ کسی نفس پر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالا جاتا پھر یہ کیوں
کہا کہ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ یعنی انسان اگر اچھا کام کرے گا تو اس کا فائدہ
اٹھائے گا اور اگر بُرا کام کرے گا تو نقصان اٹھائے گا.صرف آیت کے یا ان آیات کے الفاظ دہرا لینے سے تو مقصد پورا نہیں ہوتا بلکہ یہاں توجہ
اس طرف کروائی کہ اپنی عبادتوں اور اپنے اعمال پر ہر وقت نظر رکھنی پڑے گی اور جب یہ تو جہ ہو
گی تو اللہ تعالیٰ کے پیار کی نظر بھی اپنے بندہ پر پڑے گی.اللہ تعالیٰ کے بندہ کی ایمان میں ترقی
اسے اللہ تعالیٰ کے قریب کر رہی ہوگی اور اس کی بخشش کا سامان کرے گی نہ کہ پھر جس طرح
عیسائی کہتے ہیں اس کو کسی کفارہ کی ضرورت ہوگی.پس روزانہ پھر جس طرح یہ آیت پڑھنے
سے نیکیوں کے کمانے کی طرف توجہ رہے گی.ایک مومن رات کو جائزہ لے گا کہ کون کون سی
نیکیاں میں نے کی ہیں اور کون کون سی برائیاں کی ہیں.پھر اگر نیکیوں کی زیادہ تو فیق ملی ہوگی ،
اگر شام نے یہ گواہی دی ہو گی کہ تم نے ڈرتے ڈرتے دن بسر کیا تو شکر گزاری کے جذبے
کے تحت ایک مومن پھر اللہ تعالیٰ کے حضور مزید جھکے گا اور ایک مومن کو کیونکہ نفس کے دھو کے
کا بھی خیال رہتا ہے اس لئے وہ پھر خدا تعالیٰ سے یہ عرض کرتا ہے کہ اگر میرا جائزہ جوئیں نے
شام کو لیا ہے نفس کا دھوکہ ہے تو پھر بھی مجھ پر رحم کر اور بخش دے اور مجھے نیکیوں کی توفیق دے
اور اگر کھلی برائیاں سارے دن کے اعمال میں نظر آ رہی ہیں تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کے حضور بخشش
اور رحم کے لئے ایک مومن جھکتا ہے.430
Page 439
آیت کے اگلے الفاظ اسی طرف توجہ دلاتے ہیں اور دعا کی طرف مائل کرتے ہیں.یہ الفاظ
بھی تزکیہ نفس کے لئے جامع دعا ہیں.کیونکہ تزکیہ نفس ہی ہے جو خدا تعالیٰ کے قریب کرتا
ہے اور بندہ دعا کے ذریعہ سے پھر اللہ تعالیٰ کا قرب پاتا ہے اور یہ دعائیں کیونکہ خدا تعالیٰ نے
سکھاتی ہیں اس لئے اگر نیک نیتی سے کی ہوں اور دل سے نکلی ہوں تو اللہ تعالیٰ کے حضور قبولیت
کا درجہ پاتی ہیں.پہلے دعا یہ سکھائی کہ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا یعنی اے اللہ !
اگر ہم سے بھول چوک ہو جائے یا کوئی خطا ہو جائے تو ہمیں سزا نہ دینا.ایک مومن یہ عرض کرتا
ہے کہ ہم اپنے ایمان میں ترقی کرنے کی ہمیشہ کوشش کرتے رہیں گے.اپنی عبادتوں کے
معیار بلند کرنے کی ہمیشہ کوشش کرتے رہیں گے.تیرے تمام احکامات پر عمل کرنے کی
ہمیشہ کوشش کرتے رہیں گے.حقوق العباد کی ادائیگی کے لئے ہمیشہ کوشش کرتے رہیں
گے.لیکن پھر بھی ایک بشر ہونے کے ناطے اگر ہم کبھی غیر ارادی طور پر یا اپنی سستی کی وجہ
سے ان تمام باتوں پر عمل کرنا بھول جائیں یا اگر ہم سے ان کاموں کی ادائیگی کے دوران کوئی
غلطی ہو جائے ، نیکی کا کام کرنے کے دوران بھی شیطان پھسلا دے اور وہ نیکی دوسرے کے
لئے تکلیف کا باعث بن جائے جبکہ خود اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا ہوا ہے کہ صدقہ وخیرات
کرو لیکن ایسا صدقہ یا نیکی جس کے پیچھے تکلیف پہنچانا یا احسان جتانا ہو اس کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند
فرمایا ہے.اس دعا کے ساتھ یہ مدد مانگی کہ کبھی ایسی صورت ہو جائے تو ہمارا مؤاخذہ نہ
کرنا بلکہ ہمیں اپنے رحم اور فضل سے سیدھے راستے پر ڈال دینا تا کہ ہمارا کوئی عمل تیری رضا
کے حاصل کئے بغیر نہ ہو.پھر فرمایا رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا یعنی
اے خدا ! ہم پر وہ ذمہ داری نہ ڈالنا جو تو نے ان لوگوں پر ڈالی جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں.یعنی
ہم سے کوئی ایسا فعل سرزد نہ ہو جو تیری رضا کے خلاف ہو.ہم ہمیشہ تیرے احکامات پر عمل
کے پابند ر ہیں اور ان لوگوں کی طرح نہ بن جائیں جو ہم سے پہلے گزرے اور جنہوں نے تیرے
احکامات کو پس پشت ڈال دیا اور تیری ناراضگی کے مورد بن گئے.پس ہمیں تو ہر کام کے
431
Page 440
کرنے کے لئے تیری مدد کی ضرورت ہے.کبھی ایسا وقت نہ آئے کہ ہماری شامت اعمال
ہمیں تجھ سے دور لے جائے.کبھی ایسا وقت نہ آئے کہ ہم تیرے احکامات پر عمل کرنے والے
نہ ہوں.یہ تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا بوجھ انسان پر نہیں ڈالتا جو اس کی طاقت اور وسعت سے
باہر ہو.پس انسان کی کمزوریاں ہی اسے ان نیکیوں سے دور لے جاتی ہیں جن کے کرنے کا اللہ
تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے.تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہم نے جو تیرے سے عہد کئے ہیں وہ ہم
کبھی نہ توڑیں.جس طرح پہلے لوگوں نے توڑے اور پھر ان کو سزا کا سامنا کرنا پڑا.اضر کہ معنی
کئی ہیں جن میں سے ایک عہد اور معاہدہ بھی ہے.اس لئے اس حوالے سے میں نے یہ بات
کی ہے.اس کے علاوہ اور بھی کئی معنی ہیں مثلاً بہت مشکل قسم کا معاہدہ، بہت بڑی ذمہ داری
جس کے نہ کرنے سے پھر سزا ملے، کوئی گناہ یا جرم.اس لحاظ سے ایک مومن دعا مانگتا ہے کہ
پہلے لوگ اپنے وعدے پورے نہ کر سکے اور وہ وعدے پورے نہ کر کے، معاہدوں پر عمل نہ
کر کے، احکامات پر عمل نہ کر کے تیری سزا کے مورد بنے.اے اللہ تعالیٰ ! تو ہمیں ایسے اعمال
سے بچانا.پھر فرمایا کہ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِه کہ اے اللہ ہم پر کوئی ایسا بوجھ نہ ڈالنا جس
کی ہم میں طاقت نہیں ہے.اللہ تعالیٰ بعض دفعہ دنیا وی امتحانوں کے ذریعہ سے بھی بندوں کو
آزماتا ہے.تو یہاں اس حوالے سے بھی دعا ہے کہ اللہ تعالی کسی بھی قسم کے دنیاوی امتحان اور
ابتلاء سے ہمیں بچائے ایسا نہ ہو کہ کوئی بھی امتحان ہماری طاقت سے باہر ہو.اصل میں تو مومن
کو ہمیشہ روحانی ابتلاؤں کے ساتھ دنیاوی امتحانوں سے بھی بچنے کی دعا مانگتے رہنا چاہئے.یہ
نہیں کہ جب حالات اچھے ہوں تو یاد خدا نہ رہے.لیکن اللہ تعالیٰ بعض اوقات دنیاوی لحاظ سے
بھی مومنوں کو آزماتا ہے تو ایک مومن اس دعا کو ہمیشہ سامنے رکھتا ہے کہ میرا امتحان کسی بھی
طرح میری طاقت سے بڑھ کر نہ ہو.کیونکہ بعض دفعہ دنیاوی امتحانوں کی وجہ سے روحانی ابتلاء
بھی آ جاتے ہیں.اگر اللہ تعالیٰ نے کسی قسم کا دنیاوی امتحان لینا بھی ہے تو اتنی طاقت بھی عطا
فرمائے کہ میں اسے برداشت کر سکوں.کئی طریق سے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے.اولاد کے
432
Page 441
ذریعہ سے، مال کے ذریعہ سے، اور بہت سارے ذرائع ہیں.تو ہر صورت میں ایک مومن کو
خدا تعالیٰ کی پناہ کی تلاش کرتے رہنا چاہئے اور ہر دو قسم کے ابتلاؤں سے بچنے کے لئے یہ دعا
سکھلائی کہ یہ دعا مانگو کہ وَاعْفُ عَنَّا کہ اگر اراد یا غیر ارادی طور پر بھی ہم نے وہ کام نہیں
کئے جو ہمیں کرنے چاہئے تھے اور اس کے نتیجہ میں ابتلاء آیا ہے تو ہم التجا کرتے ہیں کہ ہماری
پردہ پوشی فرماتے ہوئے ہمیں معاف فرما اور ہمیں اس کے بداثرات سے بچالے.پھر فرمایا کہ یہ دعا کرو کہ وَاغْفِرْ لَنَا ہمیں بخش دے.غفر کے معنی ڈھانکنے کے بھی ہیں
اور اس طرح معاملے کو درست کرنے اور اصلاح کرنے کے بھی ہیں اور مٹا دینے کے بھی
ہیں.گویا یہ دعا ہے کہ اے اللہ ! ہمارے تمام ایسے کام جو تیرے نزدیک غلط ہیں ہماری
خطا معاف کرتے ہوئے ان کے بداثرات کو مٹا دے اور انہیں ختم کر دے اور آئندہ ہمیں
اپنے معاملے درست رکھنے اور ہمیشہ اصلاح کی طرف مائل رہنے کی توفیق بھی عطا فرما تا کہ
ہماری خطائیں کبھی تیری ناراضگی مول لینے والی نہ بنیں.پھر فرمایا یہ دعا کرو وارحمنا ہم پر رحم کر یعنی ہمارے سے نرمی اور مہر بانی کا سلوک رکھ محض
اور محض اپنے رحم کی وجہ سے ہماری غلطیوں کو معاف فرما اور نہ صرف معاف فرما بلکہ تیرے رحم کا تقاضا
ہے کہ اس معافی کے ساتھ ہمیں آئندہ غلطیوں سے بچنے اور اپنی رضا کے حصول
کی توفیق بھی عطا فرما،
ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرما جو تیری رضا حاصل کرنے والے ہوں تا کہ ہم ہمیشہ ان لوگوں میں
شمار ہوں جن پر تیرے پیار کی نظر پڑتی رہتی ہے اور ان غلطیوں کی وجہ سے ہماری ترقی کی رفتار کبھی کم
نہ ہو اور نہ کبھی ہماری غلطیوں کی وجہ سے ہماری ترقی رکے.انت مؤلنا تو ہمارا آقا اور مولا ہے اور تیرے علاوہ کوئی نہیں جو ہمارے سے عفو کا سلوک
کرے.مغفرت کا سلوک کرے.رحم کا سلوک کرے.یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو اپنے
بندوں سے ایک انتہا تک عفو اور مغفرت اور رحم کو لے جاتی ہے.ہماری ذاتی کمزوریوں سے
بھی جماعت پر اثر نہ آئے کیونکہ بعض دفعہ ذاتی کمزوریوں کی وجہ سے بھی لوگ جماعت پر انگلی
اٹھا رہے ہوتے ہیں اور جماعتی کمزوریاں بھی بعض دفعہ ہو جاتی ہیں.عہد یداروں کی طرف سے
433
Page 442
بھی ہو جاتی ہیں تو لوگوں کو جماعت پر انگلی اٹھانے کا کبھی موقع نہ دیں اور جب ہمارا یہ دعویٰ
ہے کہ ہم الہی جماعت ہیں اور ہماری کمزوریوں کی وجہ سے دنیا کو انگلی اٹھانے کا موقع ملے تو
پھر دنیا یہ کہے گی کہ ان لوگوں کے یہ عمل ہیں اور ان کی وجہ سے خدا تعالیٰ ان کو پکڑ رہا ہے.اللہ
تعالیٰ نے ہم پر رحم نہ کیا.ہم سے مغفرت کا سلوک نہ کیا اور سزا دی تو دنیا تو پھر یقینا یہی کہے گی
کہ ان کے عمل کی وجہ سے خدا تعالیٰ ان کو پکڑ رہا ہے اور اس دنیا میں ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا
مانگنی چاہئے کہ اگر یہ ہو گا تو پھر اس سے دنیا میں تیرا پیغام پہنچانے میں روک پیدا ہوگی.حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جو جماعت ہے اس کے سپرد تیرا یہ پیغام دنیا میں
پہنچانے کا جو بھی کام کیا گیا ہے اس میں پھر روک پیدا ہوگی.پس تجھ سے بھیک مانگتے ہیں کہ
اے ہمارے مولیٰ ! ہم سے سختی کا سلوک نہ کر.ہماری غلطیوں پر ہماری اصلاح کرتا رہ اور ہمیں
سیدھے راستے پر چلاتا رہ.اور فَانُصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِین کافروں کے خلاف بھی ہمیشہ
ہماری مدد کرتا رہ اور ان پر ہمیں غلبہ عطا فرما.ہم تو کمزور ہیں یہ غلبہ تیرے فضل اور ہم پر تیری
خاص نظر سے ہونا ہے.اس لئے ہمیں انفرادی طور پر بھی اور من حیث الجماعت بھی اُن لوگوں
میں شامل رکھ جو تیرے خاص انعام اور پیار کے ہمیشہ مورد بنے رہتے ہیں.اپنے فضل سے ایک
امتیاز ہم میں اور ہمارے غیر میں پیدا کر دے تاکہ ہمارے ماڈی معاملات بھی اور ہمارے روحانی
معاملات بھی تیر اتقویٰ اور تیرا خوف دل میں لئے ہوئے انجام پانے والے ہوں تا کہ جس مقصد کے
لئے ہم نے حضرت مسیح موعود کو قبول کیا ہے وہ مقصد حاصل کرنے والے بن سکیں.جب یہ سوچ لے کر ہم آخری دو آیات کو پڑھیں گے تو ہمارا قبلہ بھی پھر صحیح رخ پر رہے گا اور
ہم ان آیات کی برکات سے فیض پانے والے ہوں گے.ورنہ صرف الفاظ کو پڑھ لینا تو کوئی
فائدہ نہیں دیتا.نہ ہی یہ کافی ہو سکتا ہے.بے شک قرآنی الفاظ میں برکت ہے لیکن یہ برکت
نیک دل کوملتی ہے.اگر دل میں نیکی نہیں تو جس طرح نما زمیں بعض نمازیوں کے منہ پر ماری
جاتی ہیں اسی طرح اس قرآن پڑھنے والے کو جھوٹا کر کے اس کے اوپر الٹا دیا جائے گا.یہ آیات اس لئے کافی ہیں کہ انسان کا ایک مکمل جائزہ اپنے سامنے آجاتا ہے جیسا کہ
434
Page 443
میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس میں ایمان بھی ہے، دعائیں بھی ہیں، نیک اعمال بجالانے کی
طرف توجہ بھی ہے.تو اصل میں حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک بندہ اس طرح پر اپنی
زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے تو عملاً یہ اظہار کر رہا ہوتا ہے کہ میرے لئے سب کچھ
اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور پھر ایسے شخص کے لئے آنحضرت ﷺ نے ضمانت دی ہے کہ ان
آیات کا نازل کرنے والا اس بندے کے لئے کافی ہو جاتا ہے.اس کو برائیوں سے بچاتا
ہے.نیکیوں کی توفیق دیتا ہے.اس میں قناعت پیدا کرتا ہے.اس کے ہم وغم میں اسے تسلی
دیتا ہے.اسے شیطان سے محفوظ رکھتا ہے.اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں ان آیات کو سمجھتے
ہوئے ان کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.خطبہ جمعہ حضرت خلیفہ المسیح الخامس اید «الله، فرمودہ 16 جنوری 2009ء)
حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے خطبہ جمعہ فرمودہ 29 مئی
2009ء میں سورۃ البقرۃ کی آیت 287 کی تلاوت کے بعد فرمایا:
جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے
بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا.اُس کے لئے ہے جو اُس نے کمایا اور اس کا وبال بھی اُسی پر ہے جو اُس
نے ( بدی کا ) اکتساب کیا.اے ہمارے رب ! ہمارا مؤاخذہ نہ کراگر ہم بھول جائیں یا ہم سے
کوئی خطا ہو جائے.اور اے ہمارے رب ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جیسا ہم سے پہلے لوگوں پر ( ان
کے گناہوں کے نتیجہ میں ) تو نے ڈالا.اور اے ہمارے رب ہم پر کوئی ایسا بوجھ نہ ڈال جو
ہماری طاقت سے بڑھ کر ہو.اور ہم سے درگزر کر اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر.تو ہی ہمارا
والی ہے.پس ہمیں کا فرقوم کے مقابلے پر نصرت عطا کر.اس آیت کے شروع میں ہی خدا تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا
وُسْعَهَا کہ اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی صلاحیتوں اور اس کی استعدادوں سے بڑھ کر بوجھ
نہیں ڈالتا.پس وسعت کا لفظ جب انسان کے لئے بولا جاتا ہے تو اس کی محدود صلاحیتوں اور
435
Page 444
استعدادوں کو سامنے رکھتے ہوئے بولا جاتا ہے.جیسا کہ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا
ظاہر ہے.لیکن جیسا کہ میں گزشتہ خطبوں میں بتا چکا ہوں خدا تعالیٰ کے لئے واسع کا لفظ استعمال
ہوتا ہے.یہ خدا کی صفت اور نام ہے.جس کا مطلب ہے کہ صلاحیتوں کی اور استعدادوں کی
کوئی قید نہیں ہو سکتی.بلکہ اللہ تعالیٰ جہاں جامع الصفات ہے اور تمام طاقتوں اور قدرتوں کا
مالک ہے وہاں اس کی طاقتوں اور قدرتوں اور علم کی اتنی وسعت ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں.اس لئے اُن کے احاطہ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا.بہر حال اس آیت کے حوالے سے میں چند باتیں کہوں گا جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ
والسلام کی تحریرات کی روشنی میں ہیں کہ انسان کو مختلف حالات میں اس کی وسعت کے لحاظ
سے، اس کی طاقتوں اور استعدادوں کے لحاظ سے مکلف بنایا گیا ہے.کیونکہ خدا تعالی کوئی
ایسا حکم نہیں دیتا جس کو انسان بجانہ لاسکے یا اس کی طاقت اور قدرت سے بالا ہو.پس یہ انسان
کی ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کرے اور جب یہ
کوشش ہوگی تبھی ایک مومن اللہ تعالیٰ کے ان انعامات کو پانے والا ٹھہر سکتا ہے جس کا
خدا تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے.پس اسلام کی یہ خوبی ہے کہ وہ احکامات جو انسان کی طاقت اور استعدادوں کے مطابق
ہیں، دے کر ہر ایک کو اپنے اعمال کے مطابق جزا سزا کا ذمہ دارٹھہراتا ہے.اور خلاف عقل یہ
نظر یہ پیش نہیں کرتا کہ ایک معصوم نبی کو تورات کی تعلیم کے مطابق لعنتی موت مارا کہ قیامت
تک آنے والے لوگ غلطیاں کرتے رہیں، گناہ کرتے رہیں، خدا تعالیٰ کی عبادت سے غافل
رہیں ، تب بھی کوئی فکر کی بات نہیں ہے کیونکہ ایک معصوم نبی اور اللہ تعالیٰ کا فرستادہ اُن کے
ان گناہوں کے لئے لعنتی موت قبول کر چکا ہے.لیکن قرآن کریم میں خدا تعالیٰ کا کیا فطرت
کے مطابق اور حکیمانہ ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام ہر ایک کی کمزوریوں اور صلاحیتوں کے
مطابق ہیں اور پھر یہ کہ انسان کا نیک اعمال بجالانا اور ان کو بجالانے کے لئے کوشش کرنا
اسے تمام گناہوں سے کلی پاک نہیں کر دیتا.کیونکہ جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ انسان کی
رگوں میں شیطان خون کی طرح دوڑ رہا ہے.اس لئے کئی ایسے مواقع پیدا ہو سکتے ہیں کہ انسان
436
Page 445
بخشش والا
بعض غلطیاں اور گناہ غیر ارادی طور پر کرلے تو اُس کا کام ہے کہ استغفار کرتے ہوئے ان سے
بچنے کی کوشش کرے اور نیکیوں کی طرف بڑھنے کی کوشش کرے.ان اعمال کو بجالانے کی
کوشش کرے جن کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے.اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا
کرنے کے لئے ایک جدو جہد کرے تو خدا تعالیٰ جو وسیع تر رحمت والا ہے اور وسیع تریجی
ہے اپنے بندے کی طرف بخشش اور رحم کی نظر سے متوجہ ہوتا ہے.پس یہ خوبصورت تعلیم ہے جو
قرآن کریم نے ہمیں دی ہے.جس کے لئے کسی کفارہ کی ضرورت نہیں ہے.جیسا کہ میں نے
کہا تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے.اس کا
کیا مطلب ہے کہ لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا.اور یہ کس طرح اور کن کن باتوں پر حاوی
ہوتا ہے.وہ کون کون سی حالتیں ہیں جہاں انسان اپنے اعمال کا مکلف نہیں اور کہاں وہ قابل
مواخذہ ہوگا.ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی وسعت علمی سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا.گو یہاں یہ تو پتہ چلتا
ہے کہ خدا تعالیٰ کسی کی وسعت علمی سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتا.لیکن ساتھ ہی خدا تعالیٰ
فرماتا ہے کہ قُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا ( طه 115) اب یہ دعا جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی
گئی جن کو ایسا علم دیا گیا تھا جو قیامت تک کے علوم پر حاوی ہے اور جو قرآن کریم نازل ہورہا
تھا خدا تعالیٰ کے علم میں تھا کہ کیا کیا علم و عرفان کے خزانے آپ پر نازل ہونے ہیں.اُس
وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم کے نازل ہونے کے بارہ میں جلدی سے کام نہ لو بلکہ یہ دعا
کئے جا کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ علم میں ترقی دیتا رہے تاکہ علم و عرفان کا جو سمندر اللہ تعالیٰ نے آپ کے
سینے میں موجزن فرمایا تھا، اس میں وسعت پیدا ہوتی چلی جائے.اور جب قرآن کریم نازل
ہو گیا تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا تھی.تو آپ کے ماننے والوں کو اس دعا کی کس قدر
ضرورت ہے اور اپنے علم کو وسعت دینے کی کس قدر ضرورت ہے.اس کے لئے آپ نے اپنی
امت کو نصیحت بھی کی ہے کہ علم حاصل کرو خواہ اس کے لئے تمہیں چین تک جانا پڑے.(کنز اعمال کتاب العلم من قسم الاقوال باب اول في الترغیب فیہ جلد 5 جزء خامس صفحہ 60 حدیث نمبر 28693 ایڈیشن 2004، بیروت)
437
Page 446
یعنی علم کے حصول کے لئے محنت کرو.اور اپنے علم میں اضافہ کی طرف تا زندگی توجہ دیتے
رہو.بے شک
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کسی نفس کو وہ تکلیف میں نہیں ڈالتا.یعنی کسی شخص کو اس
وقت تک اس کا مکلف نہیں کرتا، اس کی جواب دہی نہیں کرتا جب تک کسی معاملہ میں اس کی
وسعت اور صلاحیت اور استعداد نہ پیدا ہو جائے لیکن ساتھ ہی یہ بھی فرمایا ہے کہ حقیقی مومن کو علم
کے حصول کی بھی کوشش کرنی چاہئے اور یہ صلاحیتیں پیدا کرنی چاہئیں اور حتی الوسع اپنے علم کو
بڑھانے کے لئے دعا بھی کرنی چاہئے.پس ایک تو وہ علم ہے جو کہ انبیاء کو خدا تعالیٰ دیتا ہے
اور سب سے بڑھ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا لیکن ساتھ ہی یہ دعا بھی سکھائی کہ
رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا.اور دوسرے وہ علم ہے جو روحانی اور دنیاوی دونوں طرح کا ہے جس کے لئے
ایک مومن کو محنت کرنی چاہئے اور ساتھ ہی دعا بھی کرنی چاہئے.اگر علم کے حصول کے لئے
محنت کی ضرورت نہیں تھی تو پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا بے معنی ہے کہ علم حاصل کرو
خواہ صعوبتیں برداشت کرنی پڑیں اور اس کے لئے سفر کرنے پڑیں.لیکن علم کے حصول کے
لئے صلاحیتیں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل کے بغیر پیدا نہیں ہوسکتیں.اس لئے دعا بھی سکھائی کہ
صرف اپنے پر بھروسہ نہ کرو بلکہ علم کے حصول کے لئے دعاؤں سے بھی خدا تعالیٰ کی مدد حاصل
کرو اور پھر جب یہ کوشش ہو گی تو ہر ایک اپنی اپنی استعدادوں اور وسائل کے لحاظ سے علم
حاصل کرے گا.دماغی صلاحیتیں بھی خدا تعالیٰ نے ہر ایک کی مختلف رکھی ہیں.بچپن کی
تربیت، اٹھان اور معاشرے کا بھی انسان پر اثر ہوتا ہے.اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس کے بھی
درجے مقرر فرمائے ہیں.ہر ایک اپنی اپنی استعداد کے لحاظ سے علم حاصل کرے اور اس
کے لئے کوشش کرے تو تب ہی تمہارے اندر وسعت پیدا ہوگی.اللہ تعالی نے اس کے
در جے مقرر فرما دیتے ہیں.یہ نہیں کہ کم ذہنی صلاحیتوں جو علم کی کمی کی وجہ سے یا قدرتی طور پر
کسی میں ہیں یا ماحول کے اثر کی وجہ سے علم میں کمی ہے.اُسے بھی اسی طرح مکلف کرے جتنا
اعلی ذہنی اور علمی صلاحیتوں والے کو اور جسے دینی اور دنیاوی علم حاصل کرنے کے تمام تر مواقع
438
Page 447
میٹر آئے ہوں.یہ تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی وسعت علمی کی وجہ سے تمام حالات کو جانتا
ہے.اس لئے جب وہ کسی کو مکلف کرتا ہے تو وہ ان سب باتوں کو مد نظر رکھ کر کرتا ہے جو کسی
بھی انسان کے بارہ میں اس کے علم میں ہیں.اگر انسان اپنی صلاحیتوں کو جو خداداد ہیں اُس علم
کے حصول کے لئے استعمال میں نہیں لاتا جس کے حاصل کرنے کا خدا تعالیٰ نے حکم دیا تھا تو
ایسا
شخص پھر جوابدہ ہے.یہاں لا يُكلف الله نفسا کا مطلب یہی ہے کہ اپنے نفس کو تم نے
اس طرح استعمال نہیں کیا جو اس کا حق بنتا تھا اور ایک مسلمان کہلانے والے کے لئے سب
سے بڑھ کر دینی علم میں ترقی ہے جس کی اس کو کوشش کرنی چاہئے.حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ طالب حق کو ایک مقام
پر پہنچ کر ہر گز
ٹھہر نا نہیں چاہئے.ورنہ شیطان لعین اور طرف لگا دے گا اور جیسے بند پانی میں عفونت پیدا ہو
جاتی ہے اسی طرح اگر مومن اپنی ترقیات کے لئے سعی نہ کرے تو وہ گر جاتا ہے.پس
سعادت مند کا فرض ہے کہ وہ طلب دین میں لگا رہے.ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے
بڑھ کر کوئی انسان کامل دنیا میں نہیں گزرا لیکن آپ " کو بھی رَبِّ زِدْنِي عِلما کی دعا تعلیم ہوئی
تھی.پھر اور کون ہے جو اپنی معرفت اور علم پر کامل بھروسہ کر کے ٹھہر جاوے اور آئندہ ترقی کی
ضرورت نہ سمجھے.“
( ملفوظات جلد دوم صفحہ 142 141 ایڈیشن 2003، مطبوعہ ربوہ )
پس یہاں لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا سے مطلب ہے اپنی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ
علم کے حصول کی کوشش کرو.اگر تم یہ کوشش کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل
کرتے رہو گے.کیونکہ وسعت علمی کی وجہ سے یعنی اُس علم کی وجہ سے جو خدا تعالیٰ کی پہچان کی
طرف مائل کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا ادراک بڑھتا ہے اور اس ادراک کی وجہ سے ایک
انسان اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے والا بنتا ہے.جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ
إِنَّمَا يَخشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَموا (فاطر (29) که یقیناً حقیقت یہی ہے کہ اللہ کے بندوں میں
سے صرف علماء اس سے ڈرتے ہیں.پس علم میں اضافہ دل میں خشیت پیدا کرتا ہے.یہاں اُن
439
Page 448
علماء کا ذکر نہیں ہورہا جو نام نہاد اور سطحی علماء ہیں.سطحی علم حاصل کر کے اپنے علم سے دوسروں کو
مرعوب کرنے کی کوشش کرتے ہیں بلکہ وہ لوگ جو جوں جوں اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنے علم
میں اضافہ ہوتا دیکھتے ہیں توں توں وسعت علمی اور خدا کی ذات کا ادراک انہیں ہوتا جاتا ہے اور
در جس طرف دیکھیں وہی راہ ہے تیرے دیدار کا کا حقیقی مفہوم انہیں سمجھ آتا ہے.حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے نا کہ ع
جس طرف دیکھیں وہی راہ ہے تیرے دیدار کا
سرمه چشم آریہ روحانی خزائن جلد 2 صفحہ 52)
یہ حقیقی مفہوم ہے جو ایک عالم کو سمجھ آتا ہے.وہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتا ہے اور تب پتہ چلتا
ہے کہ علمی لحاظ سے لا يُكلف اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا کا حقیقی مطلب کیا ہے.دوسری بات جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اس اقتباس سے میں نے اخذ کی،
جو آپ نے بیان فرمائی کہ لَا يُكَلِّفُ
اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا کہہ کر اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر
واضح فرما دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہی عقیدے پیش کرتا ہے جن کا سمجھنا انسان کی حد استعداد میں
داخل ہے تا اس کے حکم تکلیف مالا يُطاق میں داخل نہ ہوں.“
( تفسیر حضرت مسیح موعود علیہ السلام - سورۃ البقرۃ آیت 287.جلد اول صفحہ 775)
یعنی طاقت سے بڑھ کر نہ ہوں.اس آیت سے پہلی آیت میں خدا تعالیٰ نے مومنوں کے
بارے میں یہ بھی فرمایا، ایمان کی حالت کے بارے میں، عقیدہ کے بارہ میں کہ امن بالله
وَمَلَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ (البقر 2868) یعنی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اس کے فرشتوں پر
ایمان رکھتے ہیں، اس کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں اور
ایک دوسری جگہ فرمایا کہ یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں.اس بارہ میں ایک حدیث بھی ہے جو حضرت عمرؓ سے مروی ہے کہ ہم آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کے حضور بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کے پاس ایک آدمی آیا جس کے کپڑے بہت سفید
تھے اس نے آکے مختلف سوال کئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آیا اور گھٹنے ملا کر
440
Page 449
بیٹھ گیا اور پھر سوال کئے اور عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر اس کے فرشتوں پر اس کی کتابوں پر اور اس
کے رسولوں پر ایمان لائے اور یوم آخرت کو مانے اور خیر اور شر کی تقدیر پر یقین رکھے.( صحیح مسلم کتاب الایمان باب بیان الایمان والاسلام والاحسان...حدیث نمبر 8)
اب یہ باتیں ایسی ہیں کہ جن کے ماننے میں کوئی تکلیف مالا يطاق نہیں.اگر فطرت نیک
ہو، اللہ تعالیٰ کی تلاش ہو تو کائنات کیا زمین پر ہی اللہ تعالیٰ کی پیدائش کے مختلف نظارے
ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان اور یقین پیدا کرتے ہیں.اور پھر اس کا رخانہ قدرت کو دیکھتے
ہوئے ، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے رستے پر چلتے ہوئے ملائکۃ اللہ پر انسان غور کرتا ہے.تمام نظام کائنات کو دیکھتا ہے اور غور کرتا ہے تو فرشتوں کی حقیقت بھی اپنی اپنی ذہنی اور علمی
استعداد کے مطابق ہر انسان پر کھلتی چلی جاتی ہے.پھر خدا کے انبیاء پر جو کتابیں اتریں ان
پر مہر جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں قرآن کریم نے ثبت کی.اُن کی غلطیوں اور خامیوں اور تحریفوں
کی نشاندہی کی.ان کی بعض تعلیمات کی تصدیق کی اور بعض کی تردید کی.قرآن کریم کی
تصدیق اور اس کی حفاظت کا اعلان کر کے اور آج تک یہ ثابت کر کے کہ اس میں کوئی
تحریف اور تبدیلی نہیں ہوئی اور نہ ہو سکتی ہے اس پر ایمان میں پختگی پیدا کرنے کا اعلان فرمایا.اور جو تعلیم قرآن کریم میں دی، اس کے متعلق یہ اعلان فرما دیا کہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں
ہے جس پر عمل انسانی استعداد سے بالا ہو.کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے لے
کر آج تک کروڑ با مسلمانوں نے اپنی اپنی استعدادوں کے مطابق اس پر عمل کر کے دکھایا.پھر رسولوں پر ایمان ہے.اگر رسولوں کا انکار کیا گیا ، تو ان قوموں کی بد قسمتی تھی لیکن اُن کی
تعلیم اور اُن کے دعوے کبھی ایسے نہیں ہوئے جو کسی انسان کو تکلیف میں ڈالیں.ہر نبی نے
یہی کہا کہ میں اس طرح پر تمہیں خدا سے ملانے اور تمہارے فائدے کی تعلیم دینے کے لئے آیا
ہوں، اور اس کے لئے میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا.میرا اجر خدا کے پاس ہے.میرا مقصد
تمہیں تکلیف پہنچانا نہیں بلکہ تمہاری بھلائی ہے اور اس لئے کہ تم یوم آخرت پر یقین کرو اور
441
Page 450
جزا سزا کی تقدیر پر ایمان لاتے ہوئے خدا تعالیٰ کی جناب سے نیک اعمال کر کے جزا حاصل
کرو.اس کی رضا کی جنتوں میں جاؤ.اور نیک جزا میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت کس حد
تک ہے؟ فرمایا کہ کسی بھی گناہ کا بدلہ اسی قدر ہے جتنا گناہ ہے اور نیکی کا بدلہ دس گنا اور اس
سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ فرماتا چلا جاتا ہے.پس خدا تعالیٰ جو تعلیم بھی انبیاء کے ذریعہ سے دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے ان کی
استعدادوں کے مطابق ہے.اگر پہلی قوموں کی ذہنی صلاحیتیں کم تھیں تو ان کے سامنے ان کی
تعلیم بھی اس کے مطابق رکھی.اسی حوالے سے جوئیں نے بتایا کہ جبریل آئے تھے تو اسی مجلس
میں جہاں ایمان کا ذکر ہوا، فرشتے نے ارکان اسلام کا بھی ذکر کیا اور پوچھا کہ اسلام کیا ہے؟
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلمہ طیبہ لا إلهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ الله - پھر نماز کے
بارہ میں پوچھا تو آپ نے فرمایا نماز ہے.پھر روزہ ہے، پھر زکوۃ ہے، پھر حج ہے.( صحیح مسلم کتاب الایمان باب بیان الایمان والاسلام والاحسان...حدیث نمبر 8)
یہ نما ز جو عبادت ہے، روزہ جو عبادت ہے، اس کے لئے بھی کسی کو مکلف نہیں کیا.بلکہ اگر
کوئی بیمار ہے تو اس کو بیٹھ کر یا لیٹ کر بھی نماز پڑھنے کی اجازت ہے.اگر سفر میں ہے تو جمع
کرنے اور قصر کرنے کی اجازت ہے.اور اسی طرح روزہ ہے سفر میں نہ رکھنے کی اجازت
ہے.بیماری میں نہ رکھنے کی اجازت ہے.زکوۃ ہے وہ صرف اسی پر فرض ہے جو صاحب
نصاب ہے.حج ہے تو اسی پر فرض ہے جو رستے کے وسائل بھی رکھتا ہو اور امن بھی ہو صحت بھی
ہو تو اس کا حکم ہے.ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے فرمائیں وہ انسان کی طاقت کے اندر رہتے
ہوئے اس کے لئے فرض ہیں اور جیسا کہ میں نے کہا ہر طبقہ نے ان باتوں پر عمل بھی کر کے
دکھایا.قطع نظر ان کے جو مسلمان عمل نہیں کرتے کروڑ با مسلمان ایسے گزرے ہیں جو اس پر عمل
کرتے ہیں عمل کر کے دکھا رہے ہیں.اس حوالے سے تیسری بات جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان فرمائی کہ
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور نمونہ تمہارے لئے اسوۂ حسنہ
442
Page 451
ہے.جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَد كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ
(سورة الاحزاب (22) یقیناً تمہارے لئے اللہ تعالیٰ کے رسول میں اُسوہ حسنہ ہے.فرمایا کہ
ہمیں حکم ہے کہ تمام احکام میں، اخلاق میں ، عبادات میں آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی
کریں.پس اگر ہماری فطرت کو وہ قوتیں نہ دی جاتیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام
کمالات کو ظلی طور پر حاصل کر سکتیں تو یہ حکم ہمیں ہر گز نہ ہوتا کہ اس بزرگ نبی کی پیروی کرو.کیونکہ خدا تعالی فوق الطاقت کوئی تکلیف نہیں دیتا.جیسا کہ وہ خود فرماتا ہے لا يُكَلِّفُ اللهُ
نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا..(حقیقۃ الوحی روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 156 )
پس یہاں یہ فرمایا کہ تم اس نبی کی پیروی کرو.جس کی وضاحت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ
والسلام نے اس لفظ سے کی کہ ظلی طور پر یعنی وہ معیار جو تم حاصل نہیں کر سکتے لیکن اپنی اپنی
استعدادوں کے مطابق ان پر عمل کرنے اور ان کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے اس کے لئے
کوشش کرو اور یہ ہر مومن پر فرض ہے.کیونکہ یہ صلاحیت ایک مومن میں اللہ تعالی نے رکھی
ہے کہ ان نیکیوں کو بجالائے جن کا اُسوہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا ہے.صرف
یہ کہنا کہ کیونکہ وہ معیار میں حاصل نہیں کر سکتا، اس لئے کوشش کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ
بات ایک مومن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ فرائض سے آزاد نہیں کر دیتی اور جیسا کہ
میں نے کہا ہے کہ اُمت میں کروڑوں لوگوں نے یہ نمونے قائم کرنے کی کوشش کی ہے اور
کر کے دکھایا ہے کہ ایک عام مومن بھی اس اسوہ حسنہ کو جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم
فرمایا اپنی استعدادوں کے مطابق قائم کر سکتا ہے، بجالا سکتا ہے، اس پر عمل کرسکتا ہے.پھر چوتھی بات اس حوالہ سے یہ ہے کہ گو اللہ تعالی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام
انسانیت کے لئے مبعوث فرمایا ہے اور جو تعلیم وہ لائے اسے قبول کرنے کا ہر ایک کو حکم ہے اور جیسا
کہ میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہی نجات کا بھی باعث
ہے.لیکن اگر کسی پر اتمام حجت نہیں ہوا تو اللہ تعالی کیونکہ کسی کو اس کی طاقت سے بڑھ کر کسی بات کا
443
Page 452
مکلف نہیں بنا تا اس لئے وہ شخص قابل مواخذہ نہیں ہوگا جس پر اتمام حجت نہیں ہوا.لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس بارہ میں فرماتے ہیں کہ جس پر خدا تعالیٰ
کے نزدیک......اتمام حجت ہو چکا ہے وہ قیامت کے دن مؤاخذہ کے لائق ہوگا اور جس پر
خدا تعالیٰ کے نزدیک اتمام حجت نہیں ہوا اور وہ مکذب اور منکر ہے تو گوشریعت نے ( جس
کی بنا ظاہر پر ہے ) اس کا نام بھی کا فر ہی رکھا ہے اور ہم بھی اس کو باتباع شریعت کافر کے نام
سے ہی پکارتے ہیں مگر پھر بھی وہ خدا کے نزدیک بموجب آیت لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا
وُسْعَهَا قابل مواخذہ نہیں ہوگا.ہاں ہم اس بات کے مجاز نہیں ہیں کہ ہم اس کی نسبت نجات کا
حکم دیں.اس کا معاملہ خدا کے ساتھ ہے.ہمیں اس میں دخل نہیں.“
( تفسیر حضرت مسیح موعود عالسلام - سورة البقرة آيت 287 - جلد اول صفحہ 775)
یہاں یہ بھی یادر ہے کہ ان الفاظ کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی
فرمایا ہے کہ : ” علم محض خدا تعالیٰ کو ہے کہ اس کے نزدیک باوجود دلائل عقلیہ ،نقلیہ اور عمدہ
تعلیم اور آسمانی نشانوں کے کس پر ابھی تک اتمام حجت نہیں ہوا...ہمیں کسی کے باطن کا علم
نہیں ہے اور چونکہ ہر ایک پہلو کے دلائل پیش کرنے اور نشانوں کے دکھلانے سے خدا تعالیٰ
کے ہر ایک رسول کا یہی ارادہ رہا ہے کہ وہ اپنی حجت لوگوں پر پوری کرے اور اس بارے میں
خدا بھی اس کا مؤید رہا ہے اس لئے جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھ پر حجت پوری نہیں ہوئی وہ
اپنے انکار کا ذمہ وار آپ ہے اور اس بات کا بار ثبوت اُسی کی گردن پر ہے اور وہی اس بات کا
جوابدہ ہو گا کہ باوجود دلائل عقلیہ اور نقلیہ اور عمدہ تعلیم اور آسمانی نشانوں اور ہر ایک قسم کی
راہنمائی کے، کیوں اس پر حجت پوری نہیں ہوئی.“
(حقیقۃ الوحی، روحانی خزائن جلد 22 صفحه 186 تا 187 )
پس گو بغیر اتمام حجت کے خدا تعالیٰ نے کسی کو مکلف نہیں بنایا لیکن مخالفین اسلام اور
احمدیت کو یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ان کے نفس کے دھو کے انہیں یہ بات کہنے پر
مجبور تو نہیں کر رہے کہ ہم پر کوئی اتمام حجت نہیں ہوئی.دنیا میں ہر طرف فساد اور آفات، وہ
444
Page 453
نشانات تو نہیں ہیں جو خدا تعالیٰ کی طرف سے اتمام حجت کے طور پر ہیں.جبکہ زمانہ کے امام کا
دعویٰ بھی موجود ہے.پھر پانچویں بات اس ضمن میں یہ ہے کہ اللہ تعالی خلاف عقل باتوں کو ماننے پر کسی کو مجبور
نہیں کرتا اور اس وجہ سے اسے مکلف نہیں ٹھہراتا کہ کیوں یہ باتیں نہیں مانیں.قرآن کریم
میں بے شمار جگہ حکیم کا لفظ آیا ہے.ہر بات جو ہے حکمت سے پُر ہے.اس کی حکمت کی طرف
اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس کو بجالانے کا حکم دیتا ہے.جو بھی حکم اتارا ہے تمام تر حکمتوں
کے بیان سے اتارا ہے.بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مبعوث فرمایا اور جن کاموں کو
آپ کے لئے خاص کیا ان میں حکمت پھیلانا بھی ایک کام تھا.بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام
کو جو آئندہ آنے والے کے مقام کے بارہ میں دعا سکھائی گئی اُس میں بھی حکمت کو خاص
طور پر پیش نظر رکھا گیا.حکمت کیا ہے؟ عدل و انصاف کو جاری کرنا ہے.اس کا مطلب علم کو
کامل کرنا ہے.اس کا مطلب ہر بات کی دلیل پیش کرنا ہے یعنی جب کوئی حکم دیا تو اس کے
کرنے یا نہ کرنے کی وجوہات بتائیں اور یہی عقل کا تقاضا ہے.مثلاً شراب اور جوئے سے اگر روکا ہے تو روکنے کے حکم کے ساتھ فرمایا کہ يَسْئَلُونَكَ
عَنِ الْخَيْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا اثْمَّ كَبِيرُ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا
(البقرة 220) کہ وہ تجھ سے شراب اور جوئے کے متعلق پوچھتے ہیں.تو کہہ دے کہ ان
کاموں میں بڑا گناہ ہے اور نقصان ہے اور اس میں لوگوں کے لئے بعض منفعتیں بھی ہیں اور
ان کا گناہ اور نقصان ان کے نفع سے بہت بڑا ہے.اب شراب پینے سے اس لئے منع کیا گیا ہے کہ جہاں وہ انسان کو نشہ کی حالت میں لا کر
عبادتوں سے روکتا ہے وہاں معاشرے کے امن کو بھی خراب کرتا ہے.اور پھر یہ بھی اب
ثابت شدہ حقیقت ہے کہ شراب پینے والے کے جب وہ شراب کا ایک جام چڑھاتا ہے تو
دماغ کے ہزاروں خلیے متاثر ہوتے ہیں.اس لئے شراب پینے سے اس دلیل کے ساتھ منع کیا
گیا ہے اور یہی حال نجوا کھیلنے والوں کا ہے.نجوا کھیلنے والا اتنا زیادہ ایڈ کٹ (adict) ہو جاتا
445
Page 454
ہے کہ عبادت سے محروم ہو جاتا ہے اور کسی چیز کی ہوش ہی نہیں رہتی.ناجائز ذرائع سے پیسہ
حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے.وقت کا ضیاع کرتا ہے.گھریلو ذمہ داریوں سے پہلوتہی
کرتا ہے.عقل کے استعمال کی بجائے شراب اور جوئے کی برائیوں میں پڑے ہوئے جو
لوگ ہیں وہ جوش اور غصہ دکھانے والے زیادہ ہوتے ہیں.لیکن الکحل جو ہے اگر بالکل معمولی
مقدار میں انسانی فائدے کے لئے دوائیوں میں استعمال کیا جائے ، انسانی جان بچانے کے
لئے دوائیوں میں استعمال کیا جائے تو وہاں یہ کی بھی جاتی ہے.ہومیو پیتھی دوائیوں میں بھی
استعمال ہوتی ہے اور دوسری دوائیوں میں بھی.اتنی معمولی مقدار ہے کہ اس میں نشہ نہیں ہوتا.لیکن خالص شراب جو ہے وہ پینے والے چاہیں تھوڑی پئیں وہ اپنا نقصان کر رہے ہوتے ہیں
اور پھر آہستہ آہستہ یہ عادت بڑھتی چلی جاتی ہے اور تھوڑی پینے کی جو عادت ہے وہ زیادتی
میں بدلتی چلی جاتی ہے.اس لئے تھوڑی پینے کی بھی ممانعت ہے.اسی طرح اگر اسلام میں روزہ کا حکم ہے تو اس کی حکمت بھی بیان کی گئی ہے اگر انسان سوچے
تو نما ز یا روزہ کا جو حکم ہے، خدا تعالیٰ کے جو یہ احکامات ہیں یہ انسانی فائدے کے لئے ہیں.عبادت کے علاوہ اس کی صحت اور اس میں ڈسپلن پیدا کرنے کے لئے ہیں.جن کے نہ کرنے کا
حکم ہے وہ بھی فائدے کی چیزیں ہیں.جن کے کرنے کا حکم ہے وہ بھی بڑی حکمت لئے ہوئے
ہیں اور انسان کی بقا کے لئے ضروری ہیں.غرض اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں حکمت ہے اور بغیر
حکمت بیان کئے اللہ تعالیٰ کسی کو یہ نہیں کہتا کہ تم اس کام کو کرو یا نہ کرو.چھٹی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو قویٰ کی برداشت اور حوصلہ سے بڑھ کر کسی قسم کی شرعی
تکلیف نہیں اٹھوائی.مثلاً فرمایا کہ انّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَاللَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا
أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ.فَمَنِ اضْطَرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
(البقرة 174) کہ اُس نے تم پر صرف مردار ، خون ، سور کے گوشت کو اور ان چیزوں کو جن کو
اللہ کے سوا کسی اور سے نامزد کر دیا گیا ہو، حرام کیا ہے.مگر جو شخص ان اشیاء کے استعمال پر مجبور
ہو جائے اور نہ تو وہ بغاوت کرنے والا ہو اور نہ حدود سے آگے نکلنے والا ہو اس پر کوئی گناہ نہیں
446
Page 455
ے.اللہ یقیناً بڑا بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے.اب یہ حکم ہے جو عقل کے مطابق
ہے.حکمت لئے ہوئے ہے.اور انسانی قومی کی برداشت کے لحاظ سے بھی انتہائی اعلیٰ درجہ کا
ہے کہ اگر جان کا خطرہ ہے تو ان حرام چیزوں
کا استعمال کر تو سکتے ہو مگر صرف جسم کی بقا کے لئے ،
صرف سانس کا رشتہ قائم رکھنے کے لئے لیکن کوشش کرو کہ حتی الوسع ان سے بچو اور جہاں تک
ہو سکے حرام اور حلال کے فرق کو قائم رکھو.پھر ساتویں بات یہ یاد رکھنے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام انسانی طاقت کے اندر ہیں.حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں : اس آیت سے صاف طور پر پایا جاتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ کے احکام ایسے نہیں جن کی بجا آوری کوئی کر ہی نہ سکے اور نہ شرائع اور احکام
خدا تعالیٰ نے دنیا میں اس لئے نازل کئے کہ اپنی بڑی فصاحت و بلاغت اور ایجادی قانونی
طاقت اور چیستان طرازی کا فخر انسان پر ظاہر کرے.“ یعنی یہ بتائے کہ میرے میں سب
طاقتیں ہیں اور کوئی اس قسم کا معمہ پیش کرے جس کو کوئی حل نہ کر سکتا ہو اور پھر بڑے فخر سے
کہے کہ دیکھو میری بات تم سمجھ نہیں سکے.یہ نہیں ہے.فرمایا کہ نہ شرائع اور احکام خدا تعالیٰ
نے دنیا میں اس لئے نازل کئے کہ اپنی بڑی فصاحت و بلاغت اور ایجادی قانونی طاقت اور
چیستان طرازی کا فخر انسان پر ظاہر کرے.اور یوں پہلے سے ہی اپنی جگہ ٹھان رکھا تھا کہ کہاں
بیہودہ ضعیف انسان؟ اور کہاں کا ان حکموں پر عملدرآمد ؟ تو اللہ تعالیٰ نے کسی مشکل
میں ڈالنے کے لئے حکم نہیں دیئے تھے کہ کس طرح میں اپنے بندوں کو آزماؤں کہ یہ بیہودہ
انسان اور کمزور انسان کس طرح میرے حکم پر عمل کر سکتا ہے.فرمایا کہ خدا تعالیٰ اس سے برتر
66
اور پاک ہے کہ ایسا لغو فعل کرے.“
( تفسیر حضرت مسیح موعود عالسلام ( سورة البقرة آيت 287) جلد اول صفحہ 776)
پھر آٹھویں بات جو ہے اس تعلق میں یہ ہے کہ جو شرائط احکام کی بجا آوری کے لئے
خدا تعالیٰ نے لگائی ہیں وہ ہر ایک کی ذہنی ، جسمانی علمی، معاشی، روحانی وسعت کے لحاظ سے
ہیں اور ہر ایک اپنے اپنے مرتبہ علمی اور عقلی اور جسمانی اور معاشی اور روحانی کے لحاظ سے احکام بجا
447
Page 456
لانے کا پابند اور قابل مواخذہ ہے.لیکن جو فرائض اللہ تعالیٰ نے مقرر کئے ہیں انہیں اپنی اپنی
استطاعت کے مطابق بجالانا بہر حال ہر مومن پر فرض ہے.ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک دیہاتی شخص آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں
حاضر ہوا اور اسلام کے بارہ میں پوچھا.آپ نے فرما یا دن رات میں پانچ نمازیں پڑھنا.اس
پر اس نے پوچھا کہ اس کے علاوہ بھی کوئی نماز فرض ہے؟ آپ نے
فرمایا نہیں، ہاں اگر نفل
پڑھنا چاہو تو پڑھ سکتے ہو.پھر آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ماہ رمضان کے
روزے رکھنا.اس نے پوچھا اس کے علاوہ بھی روزے فرض ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں.ہاں
نفلی روزے رکھنا چاہو تو رکھ سکتے ہو.اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوۃ کا بھی ذکر
فرمایا.اس نے اس پر عرض کیا کہ اس کے علاوہ بھی مجھ پر کوئی زکوۃ ہے؟ آپ نے فرمایا
نہیں.ہاں ثواب کی خاطرتم نفلی صدقہ دینا چاہوتو دے سکتے ہو.اس پر وہ شخص یہ کہتے ہوئے چلا
گیا کہ خدا کی قسم نہ اس سے زیادہ کروں گا نہ کم.تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بیٹھے ہوئے
لوگوں کو فرمایا کہ اگر یہ سچ کہتا ہے تو اسے کامیاب و کامران سمجھو.“
(موطا امام مالك باب جامع الترغیب فی الصلاة)
تو ہر ایک کی جو جو استعداد میں ہیں اس کے مطابق وہ عمل کرتا ہے.آپ کچھ نوافل کی
تلقین بھی فرمایا کرتے تھے.پھر نویں بات یہ کہ قرآن کریم کے تمام احکامات قابل عمل ہیں.اس کا اور رنگ میں مختصر
ذکر پہلے بھی آچکا ہے.کوئی بھی ایسا حکم نہیں جو انسان پر بوجھ ہو.جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کے اسوہ پر عمل کرنے کے ضمن میں میں نے بتایا کہ حقیقی مومن اُن پر چلتا ہے اور چلنے
کی کوشش کرتا ہے.اور جیسا کہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
اخلاق اور زندگی قرآن کریم کے احکامات کی عملی تصویر ہیں.( مسند احمد بن حنبل مسند عائشہ جلد نمبر 8 صفحہ 305 حدیث نمبر 25816 مطبوعہ بیروت ایڈیشن 1998 ء )
پس اپنی اپنی حیثیت اور استعدادوں کے مطابق ہر ایک کو ان پر عمل کرنے کا حکم ہے اور
448
Page 457
یہ اللہ تعالیٰ کا دعویٰ ہے کہ کیونکہ وہ کسی مومن کو بھی بلاوجہ تکلیف میں نہیں ڈالتا اس لئے جو بھی
احکامات ہیں ہر انسان کی عمل کرنے کی طاقت کے اندر ہیں.پھر دسویں بات یہ کہ اللہ تعالیٰ سچی خوابیں بھی ہر انسان کو اس لئے دکھاتا ہے تا کہ اُسے
انبیاء کی وحی والہام کا کچھ حد تک ادراک ہو سکے.اگر کبھی سچی خواب ہی نہ آئی ہو تو وہ انبیاء کے
دعوے کو بھی محض جھوٹ سمجھے گا.حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ : ”جو نبی آتا ہے اس کی نبوت اور وحی
والہام کے سمجھنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کی فطرت میں ایک ودیعت رکھی ہوئی ہے اور وہ
ودیعت خواب ہے.اگر کسی کو کوئی خواب سچی کبھی نہ آئی ہو تو وہ کیونکر مان سکتا ہے کہ الہام
اور وحی بھی کوئی چیز ہے.اور چونکہ خدا تعالیٰ کی یہ صفت ہے کہ لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا
وُسْعَهَا اس لئے مادہ اُس نے سب میں رکھ دیا ہے.“
( تفسیر حضرت مسیح موعود عالسلام - سورة البقرة آیت 287 - جلد اول صفحه 776)
چوروں، ڈاکوؤں ، زانیوں کو بھی سچی خوابیں آتی ہیں.گیارہویں بات یہ کہ بچپن کا زمانہ اور جوانی میں قدم رکھنے سے پہلے کا زمانہ بے خبری کا
زمانہ ہے.اسی طرح جو کم عقل ہیں یا ذہنی معذور ہیں، ان کا احکامات پر عمل نہ کرنا یا اس طرح
پابندی نہ کرنا قابل مؤاخذہ نہیں ہوگا.حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ابتدائی زمانہ تو بے خبری اور غفلت کا
زمانہ ہے.اللہ تعالیٰ اس کا مواخذہ نہ کرے گا جیسا کہ خود اس نے فرما یالا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا
الَّا وُسْعَهَا.( تفسیر حضرت مسیح موعود ع الينا - سورة البقرة آيت 287 - جلد اول صفحہ 777)
بارہویں بات یہ کہ اگر جوانی اور پوری ہوشیاری اور عقل اور تمام قویٰ کی صحت کی حالت میں
اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہ ہو تو پھر یہ بات قابل مواخذہ ٹھہرے گی.حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس ضمن میں فرماتے ہیں کہ : ” ایک ہی زمانہ
449
Page 458
ہے.....یعنی شباب کا زمانہ.جوانی کا زمانہ ”جب انسان کوئی کام کر سکتا ہے کیونکہ اس
وقت قویٰ میں نشو ونما ہوتا ہے اور طاقتیں آتی ہیں لیکن یہی زمانہ ہے جبکہ نفس امارہ ساتھ ہوتا
ہے اور وہ اس پر مختلف رنگوں میں حملے کرتا ہے اور اپنے زیر اثر رکھنا چاہتا ہے.یہی زمانہ ہے
جو مواخذہ کا زمانہ ہے اور خاتمہ بالخیر کے لئے کچھ کرنے کے دن بھی یہی ہیں.لیکن ایسی
آفتوں میں گھرا ہوا ہے کہ اگر بڑی سعی نہ کی جاوے تو یہی زمانہ ہے جو جہنم میں لے جائے گا اور
شقی بنا دے گا.ہاں اگر عمدگی اور ہوشیاری اور پوری احتیاط کے ساتھ اس زمانے کو بسر
کیا جاوے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے امید ہے کہ خاتمہ بالخیر ہو جاوے.( تفسیر حضرت مسیح موعود علینا.سورۃ البقرۃ آیت 287.جلد اول صفحہ 777)
پس با وجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا جو احکام
دیئے ہیں اور جن کے نہ کرنے کا حکم دیا ہے اگر ایک انسان ان کے مطابق اپنی زندگی ڈھالنے
کی کوشش نہیں کرتا.باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی وسیع تر رحمت اور بخشش کی خوشخبری
دی ہے.اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا اور خود انسان اپنی وسعتوں اور طاقتوں کا فیصلہ کرتے
ہوئے خدا تعالیٰ کے حکم سے روگردانی کرتا ہے تو جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام
نے فرمایا ہے یہ بات جہنم میں لے جانے کا باعث بنتی ہے.اللہ تعالیٰ نے خود بھی لا يُكلف
اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا کہنے کے بعد آگے فرمایا ہے کہ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ
کہ اس نے جو اچھا کام کیا وہ بھی اس کے لئے نفع مند ہے اور جو اس نے برا کام کیا وہ بھی اس
پر و بال ہو کر پڑے گا.نیکی کے لئے كَسَبَت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جو آسانی سے ہوسکتا
ہے.اگر ارادہ ہو.کیونکہ نیکی فطرت کے مطابق ہے.لیکن بعض اوقات انسان اپنی بدقسمتی
سے فطرت کے مطابق عمل کرنے کی بجائے اکتساب کا راستہ اختیار کرتا ہے جو غیر فطری
بات ہے.اخلاقی قوتوں کو صحیح مواقع پر استعمال نہ کرنے کی وجہ سے انسان اس راستے پر چلتا
ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ آسان راستہ ہے.لیکن جب گناہوں اور
برائیوں میں دھنستا چلا جاتا ہے.پھر احساس ہوتا ہے کہ میں ایک تکلیف دہ راستے کی طرف
450
Page 459
چل پڑا ہوں.حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکتساب کا ایک یہ نکتہ بھی بیان فرمایا ہے کہ
بدیوں میں صرف اُس بدی کی سزا ملے گی جس میں اکتساب کا رنگ ہو یعنی قصداً اور ارادةً
اس کا ارتکاب کیا جائے.( تفسیر کبیر جلد دوم صفحہ 657 مطبوعہ ربوہ) اس کو نہ چھوڑے بلکہ جان بوجھ
کر اس کو کرتا چلا جائے.پس اللہ تعالیٰ نہ تو کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف میں
ڈالتا ہے اور نہ کوئی ایسے احکامات دیتا ہے جو اس کو تکلیف میں ڈالنے والے ہوں بلکہ عفو اور
در گزر اور بخشش سے کام لیتا ہے.لیکن اگر کسی بدی کے ارتکاب پر انسان کو جرأت پیدا ہواور وہ
کرتا ہی چلا جائے تو پھر اس کی سزا ہے.اس لئے ہمارے پیارے اور مہر بان خدا نے اس
آیت کے اگلے حصے میں ہمیں یہ دعا بھی سکھا دی کہ نیک کاموں کی طرف توجہ رہے جو ہر حال
میں فطرت کے مطابق ہیں اور ان پر عمل کرنا انسان کی پہنچ کے اندر بھی ہے.جیسا کہ فرمایا
رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ
مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَالًا طَاقَةَ لَنَابِهِ.وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْلَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ
مَوْلنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِين کہ اے ہمارے رب اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کر بیٹھیں
تو ہمیں سزا نہ دینا.اے ہمارے رب! اور تو ہم پر اس طرح ذمہ داری نہ ڈالنا جس طرح تو نے
ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں ڈالی اور اے ہمارے رب ہم سے وہ بوجھ نہ اٹھوا جس
کے اُٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں.ہم سے درگزر کر ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر.تو ہمارا
آتا ہے.پس کافروں کے خلاف ہماری مدد کر.تزکیہ نفس کے لئے یہ دعائیں انتہائی ضروری ہیں.کیونکہ جب تزکیہ نفس ہوگا تو لا یکلف
اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا کا صحیح ادراک بھی ہوگا.انتہائی عاجزی سے انسان یہ دعا کرتا ہے کہ اے
ہمارے خدا ان نیک باتوں کے نہ کرنے کی وجہ سے ہمیں نہ پکڑ جن کو ہم بھول گئے.ان
لوگوں کا انجام ہمیں نہ دینا جن پر تیری گرفت ہوئی تھی.اب یہ ان کا انجام نہ دینا، اس لئے نہیں
تھا کہ ہم بغاوت کرنے والے یا حد سے بڑھنے والے تھے یا تیرے حکموں کی پرواہ نہ کرنے
451
Page 460
والے تھے.بلکہ بوجہ نسیان یا بھول چوک جو انسانی فطرت کا حصہ ہے ہم اسے نہ کر سکے.اس
لئے ہمارے سے اگر کوئی بھول چوک ہوئی ہے تو ہمیں کہیں ان لوگوں میں شمار نہ کر لینا جو عادتاً
یہ کرنے والے لوگ تھے.اور پھر انتہائی عاجزی سے ایک مومن یہ دعا بھی کرتا ہے کہ اے خدا
ہم سے اُن باتوں کا مواخذہ نہ کر جو ہم نے عمدا اور جان بوجھ کر نہیں کئے.بلکہ سمجھ کی غلطی سے
ہم سے وہ عمل سرزد ہو گئے اور ہم سے جو عہد لئے ہیں جو بوجھ ہم پر ڈالے ہیں ان کا حال بھی پہلی
قوموں جیسا نہ ہو بلکہ ہمیں ہمارے عہدوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما.ورنہ ہم بھی ان لوگوں
کے زمرہ میں شامل ہو سکتے ہیں جو قابل مواخذہ ٹھہرے تھے.اور پھر باوجود اس کے کہ خدا تعالیٰ
نے فرمایا ہے کہ میں کسی جان پر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا.لیکن ایک حقیقی
مومن اور اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنے والے کا یہ کام ہے کہ اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے
خدا تعالیٰ کو اس کے اس قول کا حوالہ دیتے ہوئے یہ دعا کرے کہ کہیں میری شامت اعمال مجھے
طاقت سے بڑھ کر کسی ابتلا اور بوجھ میں نہ ڈال دے.اس لئے مجھ سے ہمیشہ درگزر کا سلوک
فرما.مجھے ہمیشہ اپنی بخشش کی چادر میں لپیٹ لے اور میں ہمیشہ تیرے رحم سے حصہ لیتا رہوں
اور جس امام کو قبول کرنے کی مجھے توفیق عطا فرمائی ہے اس پر ہمیشہ قائم رہوں اور بڑھتا چلا
جاؤں.اور میری کمزوریاں میرے دشمن کو کبھی یہ موقع نہ دیں کہ وہ میرے ایمان کو ضائع کر
سکے، یا میری وجہ سے میرے دین یا جماعت کو نقصان پہنچ سکے.بعض دفعہ ایک فرد کی غلطی
جماعت کو ابتلا میں ڈال سکتی ہے.اس لئے ہم کہہ کر تمام مومنوں کو من حیث الجماعت
ایک دوسرے کے لئے دعا کی طرف توجہ دلائی ہے تا کہ دعاؤں کا مجموعی اثر ہو اور ہر فرد کو بھی
اپنے آپ کو پاک کرنے اور ذمہ داری کو سمجھنے کی طرف توجہ پیدا ہو اور جماعت بھی مضبوط
بنیادوں پر استوار ہوتے ہوئے دشمن کے ہر شر سے محفوظ رہنے والی ہو.اللہ تعالیٰ ہمیں تمام احکامات پر ہماری تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا
فرمائے اور ان کو بجالانے کا حکم یقینا اللہ تعالیٰ نے ہماری صلاحیتوں اور استعدادوں کو دیکھتے
ہوئے دیا ہے اور صرف ہم ایک جگہ کھڑے رہنے والے نہ ہوں بلکہ ہر قسم کی وسعتوں میں
452
Page 461
خدا تعالیٰ اضافہ فرما تا چلا جائے اور من حیث الجماعت بھی ہم ترقی کی شاہراہوں پر تیزی سے
منزلیں طے کرتے چلے جائیں.اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول فرمائے.خطبہ جمعہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ، فرمودہ 29 مئی 2009ء)
حضرت خلیفہ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز فرماتے ہیں:
سورۃ بقرۃ کی آخری آیت ہے جس کی میں نے تلاوت کی ہے جس میں ہمیں اللہ تعالیٰ
نے توجہ دلائی ہے کہ یہ دعا مانگو کہ ربَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا.کہ اے ہمارے
رب! ہمیں نہ پکڑا گر ہم بھول جائیں یا ہمارے سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے.بھول جانے کے معنی ہیں کہ کوئی کام کرنا ضروری ہے لیکن نہ کیا جائے.ایک تو یہ کہ جان
بوجھ کر نہیں چھوڑا بلکہ بھول گئے.دوسرے یہ کہ ہمیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ اگر اس کو نہ کیا اور
وقت پر نہ کیا تو اس کی ہمارے لئے کتنی اہمیت ہے.اور اس خیال میں رہیں کہ کوئی بات
نہیں.نہیں کیا تو کیا ہوا، معمولی سا کام ہے.اس لئے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہے کہ ہمیں
بھولنے اور خطا کرنے سے بچا لیکن یوں بھی ہوتا ہے کہ ایک اہم کام ہے، انسان
کو تو علم نہیں
کہ کونسا اہم ہے اور کونسا نہیں، اس کے نہ کرنے سے ہماری روحانی ترقی میں فرق آ سکتا ہے،
ہمارے خدا تعالیٰ سے تعلق میں فرق آ سکتا ہے.پس اے اللہ تو ہمیں ایک تو ایسی غلطیاں
کرنے سے بچا.دوسرے اگر غلطیاں ہو گئی ہیں تو اس پر پکڑ نہ کر.اسی طرح کسی کام کے غلط
طریق سے کرنے سے یا ایسا کام کرنے سے جو ہمیں نہیں کرنا چاہئے، ہمیں پکڑ میں نہ لے.ہمارا
مؤاخذہ نہ کر.بلکہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما اور معاف فرماتے ہوئے اُن کے بداثرات
سے اور اپنی ناراضگی سے ہمیں بچالے لیکن اگر ہم جان بوجھ کر ایک غلط کام کرتے جائیں یا غلط
طریق پر کرتے چلے جائیں.اپنی اصلاح کی طرف کوشش نہ کریں اور پھر یہ دعا بھی مانگتے
ہیں تو پھر یہ دعا نہیں ہوگی بلکہ اللہ تعالیٰ اور دعا کے ساتھ ایک مذاق بن جائے گا.پس دعائیں
بہتر نتائج کے لئے ہوتی ہیں نہ کہ خدا تعالیٰ کو آزمانے کے لئے.اس لئے جہاں اپنے عمل
ہوں گے وہیں دعا بھی حقیقی دعا بنے گی.اور جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ
453
Page 462
اُس پر اُس کو کمال تک پہنچاؤ.پھر آتا ہے : رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا یعنی ہم پر
ایسا بوجھ نہ ڈال جو پہلوں پر ڈالا گیا اور اُس کی وجہ سے اُنہیں سزا ملی.یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہئے کہ اس کا نمازیں پڑھنے یا قرآنِ کریم کے جو احکامات ہیں ان
سے اس کا تعلق نہیں.اس میں یہ نہیں کہا کہ یہ ہمارے غیر معمولی بوجھ ہیں.خدا تعالیٰ نے تو پہلے
ہی فرما دیا.لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا کہ اللہ تعالیٰ اپنے احکامات انسان کی طاقت اور
وسعت کے مطابق دیتا ہے.اس بوجھ نہ ڈالنے کے یہ معنی ہیں کہ بعض جرموں کی وجہ سے پہلے
لوگوں کو سزائیں دی گئیں ، وہ سزائیں ہم پر نازل نہ ہوں.اور ہم سے وہ غلطیاں سرزد نہ ہوں جو
پہلے لوگوں سے سرزد ہوئیں اور وہ تباہ ہو گئے.اگر ہم غلطیاں بھی کرتے رہیں اور پھر کہیں کہ ہمیں
سزا بھی نہ ملے جو پہلوں کو ملی تو یہ تو نہیں ہو سکتا.یہ اللہ کے عمومی قانون کے خلاف ہے.پس یہ
دعا اور ساتھ برے اعمال سے بچنے کی کوشش ہی انسان کو اس سزا سے بچاتی ہے.پہلے لوگوں
کی خطاؤں کی وجہ سے اُن پر ایسی حکومتیں مسلط کردی گئیں جو ان کے حقوق کا خیال نہیں رکھتی
تھیں.پس ہمیں ایسے حکمرانوں سے بچا جو ہمارے لئے سزا بن گئے ہیں اور تیری ناراضگی کی وجہ
سے یہ سزا ہم پر مسلط ہے.اگر تو ناراضگی کی وجہ سے ہے تو بہت زیادہ درد سے دعائیں کرنے
کی ضرورت ہے.اگر یہ صرف امتحان ہے تو اس امتحان کو بھی ہم سے ہلکا کر دے.پھر یہ دعا سکھائی کہ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَابہ.بعض دفعہ دوسروں کی سزا کا بھی
اثر انسان پر پڑتا ہے.یا کسی نہ کسی طریقے سے اثر پہنچ رہا ہوتا ہے.اس لئے اس سے بچنے کی
بھی دعا سکھائی کہ اللہ تعالیٰ دوسروں کے قصور کی سزا کے اثرات سے بھی بچائے رکھے.لڑائی
اور جنگ میں دہشت گردی کے حملوں میں جن کو مارنا مقصود نہیں ہوتا، وہ بھی مارے جاتے
ہیں.جیسا کہ میں نے ابھی بتایا ہے، کسی خاص گروپ کو مارنا چاہتے تھے لیکن وہاں جو بھی گیا وہ
مر گیا.معصوم بچے بھی مرجاتے ہیں.حضرت مصلح موعودؓ نے بیان فرمایا ہے کہ مالا طاقة
کتابهہ کی شرط اس لئے ہے کہ یہاں ناراضگی کا سوال نہیں ، بلکہ دنیاوی مسائل اور ابتلاؤں کا
454
Page 463
ذکر ہے.ناراضگی تو خدا تعالیٰ کی چھوٹی بھی برداشت نہیں ہوتی لیکن چھوٹی تکلیف برداشت کر
لی جاتی ہے.پس روحانی سزا میں یہ دعا ہے کہ ہمیں تیری کسی ناراضگی کو برداشت کرنے کی
طاقت نہیں.مگر جب دنیاوی تکالیف کا ذکر آیا تو وہاں یہ دعا سکھائی کہ مجھے چھوٹے موٹے
ابتلاؤں پر اعتراض نہیں.میں یہ نہیں کہتا کہ ہمیشہ پھولوں کی سیج پر چلتا رہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ
نے انسان کی آزمائش کے لئے فرمایا ہے کہ میں امتحان لوں گا.البتہ وہ ابتلا جو دنیا میں تیری
ناراضگی کا موجب نہیں ہیں اور دنیا میں آتے رہتے ہیں، اُن کے بارے میں میری یہ دعا ہے کہ
ایسا نہ ہو کہ وہ ابتلا میری طاقت سے بالا ہو.مومن ابتلاؤں کی خواہش نہیں کرتا.لیکن جیسا کہ
میں نے کہا خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں مومن کو آزما تا ہوں، اس لئے آزمائش کو آسان
کرنے کی دعا بھی سکھا دی.(ماخوذ از تفسیر کبیر جلد 2 صفحہ 659) اور پھر فرمایا کہ یہ دعا کرو کہ واغف
عنا.مجھ سے عفو کر اور بد نتائج سے مجھے بچالے وَاغْفِر لنا جو غلط کام میرے سے ہو گئے ہیں اُن
کے نتائج اور اثرات سے مجھے بچالے.میرے غلط کاموں پر پردہ ڈال دے اور یوں ہو جائے
جیسے میں نے غلط کام کیا ہی نہیں.عفو کے معنی رحم کے بھی ہوتے ہیں اور جو چیز کسی انسان سے رہ جائے ، اُس کا ازالہ اسی
صورت میں ہوتا ہے کہ وہ مہیا کر دی جائے.پس وَاعْفُ عنا میں یہ فرمایا کہ میرے عمل میں
سے جو چیز رہ گئی ہے، یا میرے کام میں جو چیز رہ گئی ہے، تو اُسے اپنے رحم اور فضل سے مہیا فرما
دے.وارحمنا.یعنی جو بھی میرے سے غلطیاں ہوئی ہیں اور میری ترقی کے راستے میں روک
ہیں یا میری وجہ سے جماعتی ترقی پر اثر انداز ہو سکتی ہیں اُن غلطیوں کے متعلق مجھ پر رحم کر اور
ترقیات کے راستے میں تمام روکوں کو دور فرمادے.انت مؤلنا.کہ تو ہمارا مولیٰ ہے.ہمارا آتا ہے.لوگوں نے ہماری کمزوریاں تیری
طرف منسوب کرنی ہیں.آج دنیا میں ایک ہی جماعت ہے جس کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم جماعت
ہیں.کوئی فرد جماعت بھی جب کوئی حرکت کرتا ہے تو اُس کا اثر مجموعی طور پر بعض دفعہ
جماعت پر ہی پڑ جاتا ہے.پس اے خدا! جب لوگوں نے کمزور یاں تیری طرف منسوب کرنی
455
Page 464
ہیں،لوگوں نے یہ کہنا ہے کہ یہ الہی جماعت کہلاتی ہے، دعویٰ کرتی ہے، اُسے بھی دوسروں کی
طرح تکلیفیں پہنچ رہی ہیں اور سزائیں بھی مل رہی ہیں.پس اے مولیٰ ! تو ہمارا آقا ہے، ہم
تیرے خادم ہیں.تو ہم پر رحم کر.ہماری کمزوریاں تیری طرف منسوب ہوں گی ، لوگ سمجھیں گے
کہ یہ صرف ان کے دعوے ہیں اور نہ خدا تعالیٰ سے ان کا کوئی تعلق نہیں اور جو ہدایت اور تبلیغ کا
کام ہم کر رہے ہیں اُس میں روکیں پیدا ہوں گی ، اُس پر اثر پڑے گا اور لوگ ہدایت سے محروم
ہوجائیں گے.پس ہم رحم کی بھیک مانگتے ہیں.اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کا اقرار کرتے ہیں.تیرے سے عفو اور بخشش کے طلبگار ہیں.فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِين.پس اپنی خاص نظر ہم پر ڈالتے ہوئے ہمیں کافروں کی قوم پر
غلبہ عطا فرما.اور جولوگ ایسے کام کر رہے ہیں جس سے اسلام کی ترقی میں روک واقع ہورہی ہے اُن
پر تو ہمیں غالب کر.اور تیرے نام اور تیری تبلیغ کو ہم دنیا میں پھیلانے والے ہوں.آجکل صرف
غیر مسلم ہی نہیں یا وہ لوگ جو خدا کو نہیں مان رہے وہی اسلام کے خلاف باتیں نہیں کر رہے بلکہ
مسلمانوں میں سے بھی ایک طبقہ ایسا ہے جو اسلام کی تبلیغ کے راستے میں روک بن رہا ہے.بلکہ
مسلمانوں میں سے زیادہ ایسے ہیں جو اسلام کو بدنام کر رہے ہیں.اور غیر مسلم دنیا میں ہماری تبلیغ میں
روک بن رہے ہیں.اسلام کے نام پر جو بعض شدت پسند گروہ بنے ہوئے ہیں، یہ لوگ شدت
پسندی والا اسلام پیش کر رہے ہیں، اُس کا اثر ہماری تبلیغ پر بھی ہوتا ہے، ہورہا ہے.پس اللہ تعالیٰ
سے خاص شدت کے ساتھ اس لحاظ سے بھی دعا کی ضرورت ہے.( خطبہ جمعہ حضرت خلیفہ اسیح الخامس ایدہ اللہ، فرمودہ 8 مارچ 2013ء)
حضرت خلیفہ امسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز فرماتے ہیں:
اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا
وُسْعَهَا.(البقرۃ287) یعنی اللہ تعالیٰ کسی پر اس کی طاقت سے بڑھ کر ذمہ داری نہیں ڈالتا.پس اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ وہ کوئی ایسا حکم نہیں دیتا جو انسانی طاقت سے باہر ہو، اس کی
استعدادوں سے باہر ہو، اس کی قابلیت سے باہر ہو.پس جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے
456
Page 465
احکام آتے ہیں جن پر عمل انسانی طاقت سے باہر نہیں تو پھر ان پر عمل کی ذمہ داری انسان پر
عائد ہوتی ہے.ایک حقیقی مومن یہ عذر نہیں کر سکتا کہ فلاں حکم میری طاقت سے باہر ہے.اگر
خدا تعالیٰ پر ایمان ہے تو پھر خدا تعالیٰ کی اس بات پر بھی ایمان لازمی ہے کہ اس کے تمام
احکام ہماری استعدادوں کے مطابق ہیں اور ہمیں ان پر اپنی تمام تر استعدادوں کے مطابق عمل
کرنے کی کوشش کرنی چاہئے.یہ اسلام کی خوبصورت تعلیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا
کہ یہ حکم ہے تم اس پر عمل کر کے اس کے اعلیٰ ترین معیاروں کو ضرور حاصل کرناور نہ اس پر عمل
نہ کرنے کی وجہ سے تم سزا کے مستحق ٹھہرو گے.بلکہ یہ فرمایا کہ ہر حکم پر عمل تمہاری استعدادوں
کے مطابق ضروری ہے.اور جب ہم انسانی فطرت کا ، انسان کی حالت کا جائزہ لیتے ہیں تو پتا
چلتا ہے کہ ہر انسان کی حالت مختلف ہے.اس کی دماغی حالت، اس کی جسمانی ساخت، اس کا
علم ، ذہانت وغیرہ مختلف ہیں.پس اللہ تعالیٰ نے انسان کی کمزوریوں، اس کی حالت اور اس کی ضروریات کو سامنے رکھتے
ہوئے اپنے احکامات میں ایسی لچک رکھ دی ہے جس کے کم سے کم معیار بھی ہیں اور زیادہ سے
زیادہ معیار بھی مقرر ہیں.جب ایسی لچک ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم میرے احکامات پر دیانتداری سے
عمل کرو.پس یہ اسلام کی خوبصورت تعلیم ہے جو انسانی فطرت کو سامنے رکھتے ہوئے دی گئی ہے.کسی کو
اس اعتراض کی گنجائش نہیں رہنے دی کہ اے اللہ ! تو نے میری فطرت تو ایسی بنائی ہے، میری
حالت تو ایسی بنائی ہے اور احکامات اس سے مطابقت نہ رکھنے والے دیئے ہیں.حکم تو تو مجھے یہ
دے رہا ہے کہ اعلیٰ ترین معیار تیرے احکامات پر عمل کر کے قائم کروں اور میری جسمانی حالت
یہ ہے کہ میں اس پر عمل اس معیار کے مطابق کر ہی نہیں سکتا یا میری ذہنی حالت نہیں یا میری
اور کمزوریاں ہیں جو ان معیاروں کو حاصل کرنے میں روک ہیں، میں کس طرح اس پر عمل کر
سکتا ہوں.لیکن اللہ تعالی نے لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا کہہ کر تمام عذر ختم کر دئیے.اللہ تعالیٰ نے انسان کو بیشک اپنے احکامات، اپنی تعلیم پر عمل کا مکلف ٹھہرایا ہے.اس کو کہا
457
Page 466
ہے کہ تم ضرور کرومگر اس کا چھوٹے سے چھوٹا معیار رکھ کر اس پر عمل نہ کر کے مؤاخذہ سے بچنے
والوں کا عذر نہیں رہنے دیا.فرما دیا کہ یہ معیار تمہاری حالت کے مطابق ہیں ان پر تو بہر حال
چلنا ہے.حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس بارے میں ایک جگہ فرماتے ہیں کہ :
کوئی آدمی بھی خلاف عقل باتوں کے ماننے پر مجبور نہیں ہوسکتا.قویٰ کی برداشت اور
حوصلہ سے بڑھ کر کسی قسم کی شرعی تکلیف نہیں اٹھوائی گئی.لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا.اس آیت سے صاف طور پر پایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام ایسے نہیں جن کی بجا آوری کوئی
کر ہی نہ سکے.اور نہ شرائع واحکام خدائے تعالیٰ نے دنیا میں اس لئے نازل کئے کہ اپنی بڑی
فصاحت و بلاغت اور ایجادی قانونی طاقت اور چیستان طرازی کا فخر انسان پر ظاہر کرے.“
پہیلیاں بوجھوانی شروع کر دے.مشکل باتیں بیان کر کے انسان پر یہ فخر ظاہر کرے.)
فرمایا : ”..فخر انسان پر ظاہر کرے اور یوں پہلے ہی سے اپنی جگہ ٹھان رکھا تھا کہ کہاں بیہودہ
ضعیف انسان! اور کہاں کا ان حکموں پر عمل درآمد؟ خدا تعالیٰ اس سے برتر و پاک ہے کہ ایسا
لغو فعل کرے.“
( ملفوظات جلد 1 صفحہ 61-62.ایڈیشن 1985 ء مطبوعہ انگلستان)
پس اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو جو اعضاء دئیے ہوئے ہیں، جو طاقتیں دی ہوئی ہیں اس کے
قوی کی برداشت اور طاقت کے مطابق اپنے احکامات پر عمل کرنے کی انسان سے توقع کی
ہے.اللہ تعالیٰ کوئی ہماری طرح نہیں ہے کہ اپنا رعب قائم کرنے کے لئے حکم دے دیے.ان افسروں کی طرح جو اپنے ماتحتوں کو تنگ کرنے کے لئے بعض حکم دیتے ہیں اور نہ عمل
کرنے کی وجہ سے ان کو ذلیل ورسوا کرتے رہتے ہیں بلکہ خدا تعالیٰ کی رحمت تو اپنے بندوں پر
بیشمار ہے.انسان عمل کرے جن باتوں کے عمل کرنے کا حکم دیا ہے توکئی گنا اجر دیتا ہے اور ہر
ایک کی صلاحیت کے مطابق اس سے عمل کی توقع رکھتا ہے اور بیشمار اجر دیتا ہے.پس کیا ایسا
خدا جو اپنے بندوں پر اس قدر مہربان ہو اس کی باتوں پر عمل کرنے کی انسان کو اپنی استعدادوں
458
Page 467
کے مطابق کوشش نہیں کرنی چاہئے؟ یقینا ایک حقیقی مومن اس کے لئے کوشش کرے گا اور
کرنی چاہئے.پھر ایک جگہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا کی وضاحت
کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ : ”شریعت کا مدار نرمی پر ہے سختی پر نہیں.“
( ملفوظات جلد 3 صفحہ 404.ایڈیشن 1985 مطبوعہ انگلستان )
یعنی ہر ایک سے اس کی استعدادوں کے مطابق معاملہ کیا جائے گا.شریعت نرمی اور آسانی
دیتی ہے.پس اللہ تعالیٰ نے استعدادوں کے مطابق عمل کا کہہ کر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی
کی حد مقرر کر دی.یہ حد بندی کر دی.ہر ایک کی اپنی ذہنی اور علمی حالت کے مطابق انسانی
عقلوں کی بھی حد بندی کردی.کاموں کی بھی حد بندی کردی سوائے اس کے کہ انسان ذہنی بیمار
ہو یا پاگل ہو.چھوٹی سے چھوٹی عقل رکھنے والے کے لئے بھی اس کے مطابق عمل کا کہا ہے جو
اس کی صلاحیتیں ہیں، جو اس کی استعدادیں ہیں.اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ہر انسان ایمان
حاصل کرے.اس لئے اس نے چھوٹی سے چھوٹی عقل کا بھی معیار قائم کیا کہ جو جس کی
صلاحیت ہے اس کے مطابق اس کو ایمان تو بہر حال حاصل کرنا چاہئے.اگر وہ چھوٹی سے
چھوٹی عقل کا بھی معیار مقرر نہ کرتا پھر سب لوگ ایمان لانے کے مکلف نہ ہوتے.ان پر
لازمی نہ ہوتا کہ ضرور ایمان لائیں.صرف وہی اس کے مکلف ہوتے جو عقل کے اونچے معیار
کے ہیں جن کی صلاحیتیں اور استعداد میں بہت زیادہ ہیں.اگر کسی شخص کو کوئی بات سمجھ نہ آئے
تو پھر اس پر عمل نہ کرنے کا الزام عائد نہیں ہوتا.اس لئے خدا تعالیٰ نے ادنی عقل سے لے کر
اعلی عقل تک مختلف درجوں کے لحاظ سے معیار رکھے ہیں.کوئی بڑا عقلمند ہے.کوئی کم عقلمند
ہے.کسی میں زیادہ صلاحیتیں استعداد میں ہیں.کسی میں کم ہیں.دنیا داری کے معاملات میں
بھی ہم دیکھتے ہیں.اسی دماغی رجحان اور حالت کے مطابق کوئی اعلیٰ کام کرنے کی صلاحیت
رکھتا ہے اور یہ صلاحیت رکھتے ہوئے بہت آگے نکل جاتا ہے.کوئی درمیان میں رہتا ہے.459
Page 468
کوئی بہت پیچھے رہ جاتا ہے.پھر پیشوں کے لحاظ سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی کسی پیشے میں
آگے نکلنے کی صلاحیت رکھتا ہے کوئی کسی پیشے میں تعلیم کے لحاظ سے کسی کا رجحان کسی مضمون
کی طرف ہوتا ہے، کسی کا کسی طرف.تو یہ ایک فطری چیز ہے کہ رجحان مختلف کاموں کے
کرنے اور ان میں کامیابی حاصل کرنے کی طرف لے جاتے ہیں.بہر حال کوئی انسان برابر
نہیں ہوسکتا.اللہ تعالیٰ نے برابر پیدا ہی نہیں کیا ، نہ حالات اس کو برابر رکھ سکتے ہیں.انسانوں
کی صلاحیتوں میں فرق ہوتا ہے.برابر مواقع بھی دئیے جائیں تو تب بھی کوئی آگے نکل جاتا
ہے کوئی پیچھے رہ جاتا ہے.عقل کے علاوہ بھی بعض عوامل کارفرما ہوتے ہیں.یہی حالت
ایمان کی بھی ہے.جس طرح ظاہری طور پر ہوتا ہے اس طرح ایمان میں بھی یہی ہوتا ہے.اللہ
تعالیٰ کے احکامات پر عمل کی بھی یہی حالت ہے.اپنی اپنی صلاحیتوں اور استعدادوں کے
مطابق کوئی آگے نکل جاتا ہے، کوئی پیچھے رہ جاتا ہے.ہم یہ امید تو سب سے کر سکتے ہیں کہ
سب ایمان لے آئیں لیکن یہ نہیں ہو سکتا ہے نہ یہ کیا جا سکتا ہے کہ سب کا ایمان اور عمل کا
معیار ایک جیسا ہو جائے.اللہ تعالیٰ یہ تو فرماتا ہے کہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے.قرآن
کریم میں بھی ذکر ہے.کیوں اپنی عاقبت خراب کرتے ہیں.لیکن یہ مطالبہ قرآن کریم میں
نہیں ہے کہ ہر ایک حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مومن
کیوں نہیں بنتے.ایک روایت میں آتا ہے ایک شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور
اسلام کے متعلق پوچھا.آپ نے فرمایا دن رات میں پانچ نمازیں پڑھنا فرض ہے.اس
نے پوچھا اس کے علاوہ بھی کوئی نما ز فرض ہے؟ آپ نے فرمایا: نہیں.اگر نفل پڑھنا چاہو تو
پڑھ سکتے ہو.پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ماہ کے روزے رکھنا فرض ہے.اس نے پوچھا اس کے علاوہ بھی کوئی روزے فرض ہیں ؟ آپ نے فرمایا: نہیں.ہاں نفلی
روزے رکھنا چاہو تو رکھ سکتے ہو.اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوۃ کا بھی ذکر
فرمایا.اس پر اس نے پوچھا.اس کے علاوہ بھی مجھ پر کوئی زکوۃ ہے؟ آپ نے فرمایا:
460
Page 469
نہیں.ہاں ثواب کی خاطر تم نفلی صدقہ دینا چاہو تو دے سکتے ہو.یہ باتیں سن کر وہ شخص یہ کہتے
ہوئے واپس چلا گیا کہ خدا کی قسم ! نہ اس سے زیادہ کروں گا نہ کم.آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ اگر یہ سچ کہتا ہے تو اس کو کامیاب سمجھو.( صحیح البخاری کتاب الایمان باب الزكاة من الاسلام حدیث نمبر 46)
آپ نے اس کو فلاح پانے والا کہا اور یہ کہہ کر جنت کی بشارت دی.پس اس بات سے پتا چلتا ہے کہ اسلام نے ہر ایک سے حضرت عمرؓ اور حضرت
ابوبکر جیسے
ایمان کا مطالبہ نہیں کیا.ہر ایک کے مختلف درجے ہیں.ہر ایک کی طاقتیں ہیں.ہر ایک کے
ایمان کے معیار ہیں.حضرت ابوبکر زکوۃ کے علاوہ بھی گھر کا اپنا سارا مال اٹھا کے لے آتے
ہیں.حضرت عمر سمجھتے ہیں آج میں آگے نکل جاؤں گا اور آدھا مال گھر کالے آتے ہیں.لیکن
جب دیکھا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام لے کر آئے ہوئے تھے.( سنن الترمذی ابواب المناقب باب نمبر 43 حدیث نمبر 3675)
تو یہاں بھی ہر ایک کے معیار ہیں.ہاں یہ بیشک ہے کہ ایسے اعلیٰ معیار کا مطالبہ ہر ایک
سے نہیں ہوسکتا.لیکن تحریص دلائی گئی ہے.بتایا گیا ہے کہ نوافل کا ثواب ہے.بلکہ یہ بھی کہا
که نوافل فرائض کی کمی کو بھی پورا کرتے ہیں.ایمان ویقین میں اضافہ کرتے ہیں.لیکن یہ حکم
نہیں دیا گیا کہ ضرور ہر ایک کے لئے فرض ہے چاہے اس کی حالت ہے کہ نہیں کہ نفل ادا
کرے.یعنی جو بھی فرائض میں داخل ہے صرف نفل نمازوں کے ( معاملہ میں ) نہیں بلکہ مالی
قربانی کے لئے بھی ، وقت کے لئے بھی.کیونکہ اعلیٰ درجوں پر عمل جو ہے اسلام میں قابلیتوں کی
بنا پر ہے.اس لئے ہر ایک کے لئے فرض نہیں ہے اور چونکہ قابلیتیں مختلف ہوتی ہیں اس
لئے کم سے کم قابلیت اور عقل جو سب میں ہوتی ہے اس کے مطابق مطالبہ کیا گیا ہے.ایمان
کے اعلیٰ مدارج کا ہر ایک سے مطالبہ نہیں کیا گیا.جو ( مدارج ) کسی بھی اعلی سے اعلیٰ ایمان
رکھنے والے کے اپنے اعلیٰ معیار کے مطابق ہوں، کم سے کم ایمان رکھنے والے کا جو اعلیٰ ترین
معیار ہے اس کو وہاں تک پہنچنے کے لئے نہیں کہا گیا.پس یہ فرق ہے جو صلاحیتوں اور
461
Page 470
قابلیتوں کے مطابق رکھا گیا ہے اور کسی کو تکلیف میں نہیں ڈالا گیا.حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ فرمایا کہ : ”خدا تعالیٰ انسانی نفوس کو
ان کی وسعت علمی سے زیادہ کسی بات کو قبول کرنے کے لئے تکلیف نہیں دیتا اور وہی عقیدے
پیش کرتا ہے جن کا سمجھنا انسان کی حد استعداد میں داخل ہے تا اس کے حکم تکلیف مالا يطاق میں
داخل نہ ہوں.“
اسلامی اصول کی فلاسفی روحانی خزائن جلد 10 صفحہ 432)
پس ہر ایک کے عمل اور سمجھ کی جو استعداد کی حد ہے وہی اس کی نیکی کا معیار ہے کیونکہ اللہ
تعالی طاقت سے بڑھ کر کسی کو تکلیف میں نہیں ڈالتا.یہاں یہ بھی واضح ہونا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر ہمارے دل کی پاتال تک ہے، گہرائی تک
ہے.کسی بھی قسم کا بہانہ اپنی کم علمی یا کم عقلی یا استعدادوں کی کمی کا اللہ تعالیٰ کے حضور نہیں چل
سکتا.اس لئے اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے پھر اپنی استعدادوں کے جائزہ لے کر اپنے
ایمان اور عمل کو پرکھنا چاہئے.یہی نہیں کہ تھوڑے سے تھوڑا معیار ہے تو بس ہمیں چھٹی مل
گئی.کم از کم معیار بھی جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا وہ یہ تھا کہ پانچ نمازیں
فرض ہیں.اور ایک مرد کے لئے پانچ نمازیں باجماعت فرض ہیں.روزے فرض ہیں اور اگر
مال
پر قربانی یا زکوۃ لگتی ہے تو وہ بھی فرض ہے.پس یہ کم از کم معیار ہیں.پس ان معیاروں کو
سامنے رکھتے ہوئے اپنے جائزے لے کر ہر ایک کو پرکھنا چاہئے.جیسا کہ میں نے کہا اس حدیث میں اس شخص نے کہا تھا کہ نہ اس سے زیادہ کروں گا نہ کم تو
وہ کم از کم معیار تھا جس کا اس نے اعلان کیا تھا.ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں جو نما ز بھی
اللہ تعالیٰ کے حکم کے موافق ادا نہیں کرتے جو فرض ہے جیسا کہ میں نے کہا مردوں کو باجماعت
نماز فرض ہے.پس ہمیشہ یاد رکھنا چاہئے کہ خدا تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا.جس طرح دنیا کے کاموں
کے لئے کوشش ہوتی ہے اس سے بڑھ کر دین کے کام کے لئے کوشش ہونی چاہئے اور
462
Page 471
استعدادوں کو بڑھانے کی بھی کوشش ہونی چاہئے.دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کمز ور لوگ ہمیشہ
اپنے لئے سہارے کی تلاش کرتے ہیں لیکن کیونکہ صلاحیتیں مختلف ہوتی ہیں اس لئے بعض
لوگ جن میں کچھ قابلیت ہو آگے بڑھ جاتے ہیں لیکن بعض مزید سہارے کو چاہتے ہیں لیکن یہ
نہیں ہوتا کہ وہ تھک کر اس لئے بیٹھ جائیں کہ ان کی صلاحیت ہی اتنی تھی.دنیاوی قانون میں تو
ممکن ہو سکتا ہے کہ صلاحیت سے زیادہ کا وزن کسی پر ڈالا جار ہا ہولیکن دین کے معاملات میں یہ
نہیں ہے.جیسا کہ ذکر ہوچکا ہے کہ کم از کم معیار کے بعد یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوسکتا کہ
صلاحیت سے زیادہ کا بوجھ کسی پر لادا جارہا ہو.ہاں بعض باتوں کو سمجھنے کے لئے بعض سہاروں
کی ضرورت پڑ سکتی ہے.جیسا کہ دنیاوی معاملات میں پڑتی ہے.ان سہاروں کی طرف کمزور
مومنوں کو رجوع کرنا چاہئے اسی طرح جس طرح ایک کمز ور طالب علم استاد سے بار بار کوئی سبق
سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اور استاد کی کوشش سے ان کے معیار بہتر ہو جاتے ہیں لیکن استاد
مدد نہ کرے تو بالکل پیچھے رہ جاتے ہیں لیکن ایسے استاد جو مدد نہ کریں ان کے رویے سے یہ بات
واضح ہو جاتی ہے کہ وہ استاد صحیح طور پر اپنے فرائض اور اپنا حق ادا نہیں کر رہے بلکہ اپنے کام سے
خیانت کرنے والے استاد ہیں.یہاں میں دین کے لئے جو استاد مقرر ہیں ان کو بھی تو جہ دلانا چاہتا ہوں یعنی ہمارے مربیان
و مبلغین اور صاحب علم لوگ کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کی استعدادوں کو بڑھایا ہوا ہے تو وہ ان کا صحیح
استعمال بھی کریں اور اپنی استعدادوں سے کمزوروں کی استعدادوں کو علمی لحاظ سے بڑھانے کی
کوشش کریں کیونکہ یہ آپ کی طرف سے خدا تعالیٰ کی عطا کردہ صلاحیتوں کا شکرانہ ہوگا.اگر
اللہ تعالی کی حقیقی رنگ میں شکر گزاری نہ ہو تو انسان گنہگار بن جاتا ہے.( خطبہ جمعہ حضرت خلیفہ المسیح الخامس ایدہ اللہ ، فرمود 30 جنوری 2015ء)
463
Page 473
XXXXXXXXXXXX
سورة آل عمران آیات 26 تا 31
فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنُهُمْ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ 26.جب ہم اس دن کہ جس کی آمد ) میں کوئی
شک ( وشبہ ) نہیں انہیں جمع کریں گے تو ان کا کیا
فِيْهِ ۖ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ حال ہوگا اور ہر شخص نے جو کچھ کمایا ہو گا ( اس دن )
وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ )
وہ اسے پورا پورا دے دیا جائے گا اور ان پر ( کچھ
بھی ) ظلم نہیں کیا جائے گا.قُلِ اللهُمَّ مُلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ 27.تو کہہ اے اللہ ! جو سلطنت کا مالک ہے تو جسے
تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ چاہتا ہے سلطنت دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے
سلطنت لے لیتا ہے.جسے چاہتا ہے غلبہ بخشا ہے اور
وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے.سب بھلائی تیرے ہی
الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
ہاتھ میں ہے.اور تو یقینا ہر ایک چیز پر قادر ہے.تُولِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي 28.تورات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات
الَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ
میں داخل کرتا ہے اور بے جان سے جان دار نکالتا ہے
اور جان دار سے بے جان نکالتا ہے اور جسے چاہتا ہے
وَتُخْرِجُ الْمَيْتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ بے حساب دیتا ہے.تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ
لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَفِرِينَ أَوْلِيَاءَ 29.مومن مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ
بنائیں.صرف ان سے پوری طرح بچ کر رہنا
مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ
تمہارے لئے جائز ہے اور ( تم میں سے ) جو شخص ایسا
فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا کرے اس کا اللہ سے کسی بات میں بھی ( کوئی تعلق )
مِنْهُمْ تُقَةٌ وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ نہ ہوگا.اور اللہ تمہیں اپنے عذاب سے ڈراتا ہے.اور
وَإِلَى اللهِ الْمَصِيرُ
اللہ ہی کی طرف ( تمہیں ) کو ٹنا ہوگا.465
Page 474
قُلْ اِنْ تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ 30.تو (ان سے) کہہ دے (کہ) جو (کچھ)
يَعْلَمُهُ اللهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَواتِ وَمَا
تمہارے سنیوں میں ہے اسے خواہ چھپاؤ یا اسے
ظاہر کرو (بہر حال ) اللہ اسے جان لے گا.اور جو
فِي الْأَرْضِ ۖ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ کچھ (بھی) آسمانوں میں ہے وہ اسے اور جو کچھ
زمین میں ہے اسے (بھی) جانتا ہے.اور اللہ ہر
ایک چیز پر بڑا قادر ہے.يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ 31.( اس دن سے ڈرو ) جس دن ہر شخص ہر نیکی
مُحْضَرًا ۚ وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوْءٍ ۚ تَوَدُّ کو جو اس نے کی ہوگی (اپنے) سامنے موجود
پائے گا.اور جو بدی اس نے کی ہوگی اسے بھی.لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَةَ أَمَدًا بَعِيدًا
وہ خواہش کرے گا کہ کاش اس ( بدی) کے اور
وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ اس کے درمیان لمبا فاصلہ ہوتا.اور اللہ تمہیں
بِالْعِبَادِي
اپنے عذاب سے ڈراتا ہے اور اللہ بندوں پر
شفقت کرنے والا ہے.466
Page 475
قل اللهم لك الْمُلْكِ تُونِي الْمُلْكَ مَن تَشَاء وَتَارِعُ الْمُلْكَ مَن
تَهَاء وَتُعِزُّ مَنْ نَهَاء وَتُذِلُّ مَن نَهَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ
(آل عمران: 27)
حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں:
کہہ اے بار خدایا! اے مالک الملک ! تو جسے چاہتا ہے ملک دیتا ہے اور جس سے چاہتا
ہے ملک چھین لیتا ہے تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے.ہر یک
خیر کہ جس کا انسان طالب ہے تیرے ہی ہاتھ میں ہے.تو ہر یک چیز پر قادر ہے.( براہین احمدیہ ، روحانی خزائن جلد 1 ، صفحہ 261 حاشیه (11)
وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ یعنی خدا جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو
چاہتا ہے ذلت دیتا ہے.ست بچن ، روحانی خزائن جلد 10 ، صفحہ 232)
تويج اليْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولج النهار في اليْلِ وَتُخْرِجُ الْحَق مِن
الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيْتَ مِنَ الْحَقِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ
حِسَابِ (آل عمران: 28)
جاننا چاہئے کہ خدائے تعالیٰ نے اس بات کو بڑے پر زور الفاظ سے قرآن شریف
میں بیان کیا ہے کہ دنیا کی حالت میں قدیم سے ایک مڈ وجزر واقعہ ہے اور اسی کی طرف اشارہ
ہے جو فرمایا ہے : تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَ تُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ یعنی اے خدا! کبھی تو رات کو
دن میں اور کبھی دن کو رات میں داخل کرتا ہے یعنی ضلالت کے غلبہ پر ہدایت اور ہدایت کے
غلبہ پر ضلالت کو پیدا کرتا ہے.467
Page 476
اور حقیقت اس مدوجزر کی یہ ہے کہ کبھی بامر اللہ تعالیٰ انسانوں کے دلوں میں ایک صورت
انقباض اور محجوبیت کی پیدا ہو جاتی ہے اور دنیا کی آرائشیں ان کو عزیز معلوم ہونے لگتی ہیں اور
تمام ہمتیں ان کی اپنی دنیا کے درست کرنے میں اور اس کے عیش حاصل کرنے کی طرف
مشغول ہو جاتی ہیں.یہ ظلمت کا زمانہ ہے جس کے انتہائی نقطہ کی رات لیلہ القدر کہلاتی ہے اور
وہ لیلہ القدر ہمیشہ آتی ہے مگر کامل طور پر اس وقت آئی تھی کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کے ظہور کا دن آپہنچا تھا کیونکہ اس وقت تمام دنیا پر ایسی کامل گمراہی کی تاریکی پھیل چکی تھی جس
کی مانند کبھی نہیں پھیلی تھی اور نہ آئندہ کبھی پھیلے گی جب تک قیامت نہ آوے.غرض جب یہ
ظلمت اپنے اس انتہائی نقطہ تک پہنچ جاتی ہے کہ جو اس کے لئے مقدر ہے تو عنایت الہیہ تنویر
عالم کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور کوئی صاحب نور دنیا کی اصلاح کے لئے بھیجا جاتا ہے اور جب
وہ آتا ہے تو اس کی طرف مستعد روحیں کھینچی چلی آتی ہے اور پاک فطرتیں خود بخو درو بحق ہوتی
چلی جاتی ہیں اور جیسا کہ ہر گز ممکن نہیں کہ شمع کے روشن ہونے سے پروانہ اس طرف رخ نہ
کرے ایسا ہی یہ بھی غیر ممکن ہے کہ بروقت ظہور کسی صاحب نور کے صاحب فطرتِ سلیمہ کا اس
کی طرف بارادت متوجہ نہ ہو.ان آیات میں جو خدائے تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، جو بنیادِ
دعوی ہے اُس کا خلاصہ یہی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے وقت ایک ایسی
ظلمانی حالت پر زمانہ آچکا تھا کہ جو آفتاب صداقت کے ظاہر ہونے کے متقاضی تھے.حضرت خلیفہ المسیح الاول رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں :
( براہین احمدیہ، روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 645 تا 647)
قُلِ اللَّهُمَّ مُلِكَ الْمُلْكِ : خدا کے تمام وعدے اعمال کے ساتھ وابستہ ہیں اور اعمال
کی توفیق دعاؤں سے حاصل ہوتی ہے.اس لئے دعا سکھائی ہے.قرآن کی دعائیں یا تورب،
رَبَّنَا سے شروع ہوتی ہیں یا اللھم سے.عام دُعا جو ہر نماز میں مانگی جاتی ہے وہ بھی اللھم
468
Page 477
سے ہی شروع ہوتی ہے.اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ.ضمیمه اخبار بدر قادیان 27 مئی 1909ء)
انسان چاہتا ہے کہ دنیا میں معربا ز اور محترم بنے لیکن حقیقی عزت اور پیٹی تکریم خدا
تعالیٰ سے آتی ہے.وہی ہے جس کی یہ شان ہے تُعِزُّ مَنْ نَهَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ
( الحكم 10 مئی 1905 ، صفحہ 5)
تُوج اليْلَ فِي النَّهَارِ : وہ چاہے تو جن کے گھر غموں کی اندھیری ہے وہاں آرام کا دن
چڑھا دے اور چاہے تو جہاں راحت کی روشنی ہے وہاں دُکھوں کی تاریکی کر دے.وہ چاہے تو
بروں سے بھلے اور پھلوں سے بُرے بناوے.جسے چاہے عزت دے جسے چاہے ذلیل
کرے.یہ دُعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وصحابہ نے مانگی.خدا نے ان کو عزت دی.نیک و
ممتاز انسان بنایا.یہاں جہاد کے متعلق یہ ہدایت کی ہے کہ دُعا ضروری ہے.پھر افترا نہ کرے.خدا تعالیٰ کا
صریح نافرمان نہ ہو.ضمیمه اخبار بدر قادیان 27 رمئی 1909ء)
لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ.وَمَنْ
يَفْعَلُ ذلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً.وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ.وَإِلَى اللهِ الْمَصِيرُ (آل عمران: 29)
لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ : مومن کبھی کافروں کو اپنے دلوں پر متصرف نہ
مانے.پارہ 28 سورہ ممتحنہ میں اسے اور بھی کھول کر بیان کیا ہے.شروع سے سورۃ کو پڑھ کر
دیکھ لو.إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً : اسلام میں جتنے مسائل ہیں ان میں حفظ نفوس، حفظ اموال،
حفظ اعراض مقصود ہوتا ہے.یہاں بھی ایک گر بتا دیا.(ضمیمه اخبار بدر قادیان 27 مئی 1909ء)
469
Page 478
يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ
تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ
تعول بِالْعِبَادِ
ا محضرا : نتیجہ سامنے دیکھے گا.اس سے آگے وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ کے لئے مُحْضَرًا
نہیں فرمایا.یہ اس کی شان ستاری کا تقاضا ہے.(ضمیمه اخبار بدر قادیان 27 رمئی 1909ء)
(ماخوذ از حقائق الفرقان )
حضرت خلیفۃ اسیح الرابع رحمہ اللہ فرماتے ہیں:
پھر آنحضرت علی کو خدا تعالیٰ نے خود یہ دعا سکھائی : قُلِ اللَّهُمَّ مُلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي
الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ
الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.تُولِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُوْجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَقَّ
مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ - وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ
(آل عمران: 28-27)
سے محمد عالم تو مجھ سے یوں مخاطب ہوا کر مجھ سے یہ دعا کیا کر کہ اے ہمارے اللہ !
تو ملک کا مالک ہے.یعنی ہر قسم کی ملکیت جس کا تصور کیا جاسکتا ہے وہ تیرے قبضہ قدرت میں
ہے.تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ اور دنیا کی بادشاہتیں بھی اور آخرت کی بادشاہتیں بھی تیری طرف
سے عطا ہوتی ہیں جس کو جو چاہے جس طرح چاہے تو عطا فرمادے خواہ وہ اس دنیا کا ملک ہو یا
آخرت کا ملک ہو.وَ تَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَن تَشَاءُ لیکن تو چھینے کی بھی طاقت رکھتا ہے جب
چاہے کسی کو نا اہل قرار دے کر اس سے اپنا عطا کردہ ملک واپس لے لے.وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَ
تُذِلُّ مَن نَشَاءُ تو جس کو چاہتا ہے عزت بخشتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اسے ذلیل ہونے
دیتا ہے لیکن بيدك الخير - تیرے ہاتھ میں خیر ہے.بھلائی ہے.تیری طرف سے کسی کو ذلت
470
Page 479
نہیں پہنچتی.تو ذلیل ہونے دیتا ہے.یعنی اگر وہ خود ذلیل ہونا چاہتا ہے تو بعض دفعہ تو فیصلہ
فرمالیتا ہے کہ اچھا پھر ہم تجھے ذلیل ہونے دیں گے اور پھر وہ ذلیل اور رسوا ہو جاتا ہے لیکن
جہاں تک تیرے ہاتھ کا تعلق ہے یہ ہاتھ خیر کا ہاتھ ہے یہ برائی کا ہاتھ نہیں ہے.إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
قدیر.اور تو ہر چیز پر قادر ہے جو تو چاہتا ہے اور چونکہ تو بھلائی چاہتا ہے اس لئے ہم تجھ سے
بھلائی ہی کی توقع رکھتے ہیں.تُولِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ زمانے ادلتے
بدلتے رہتے ہیں راتیں دنوں میں داخل ہو جاتی ہیں اور دنوں کو تو راتوں میں داخل فرما دیتا ہے
جب چاہے راتوں کو دنوں میں داخل فرماتا ہے.دنوں کو راتوں میں داخل فرما دیتا ہے.و تُخْرِجُ الْحَى مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيْتَ مِنَ الحتي.اور اسی طرح تو زندوں کو مردوں میں
داخل کر دیتا ہے اور مردوں کو زندوں میں داخل فرما دیتا ہے.پس ہر آن تیر افضل ہی ہے جو
ہمیں ہمیشہ صحیح رستے پر قائم رکھے اور مردوں سے زندوں میں داخل ہونے والے ہوں نہ کہ
زندوں سے مردوں میں داخل ہونے والے.اسی طرح ہمارے زمانے راتوں سے روشنیوں
میں تبدیل ہونے والے ہوں، روشنیوں سے راتوں میں تبدیل ہونے والے نہ ہوں.وترزُقُ
مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ.اور تو جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے اسے رزق عطا فرماتا ہے.آنحضرت علی نے اس کے متعلق فرمایا کہ جو شخص سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے،
پھر آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے ، پھر آل عمران کی اس آیت کی تلاوت کرتا ہے جس
میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ
لا إِلهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ( آل عمران : 19) شَهِدَ اللهُ اللہ تعالیٰ اس بات کا گواہ ہے أَنَّهُ لَا إِلَهَ
إِلَّا هُوَ کہ اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں وَالْمَلَائِكَةُ اور فرشتے بھی اس بات کے گواہ ہیں اور
وَأُولُو الْعِلْمِ اور جتنے صاحب علم لوگ ہیں وہ بھی اس بات کے گواہ ہیں.قائما بِالْقِسْطِ خدا
تعالیٰ اور خدا تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے سارے ہمیشہ انصاف پر قائم رہتے ہیں اور وہ
هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے.471
Page 480
اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں اور پھر یہ دعا پڑھتے ہیں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے
پڑھی ہے فرمایا: جو شخص بھی ہر فرض نماز کے بعد یہ دعائیں کرے گا اس کے لئے اللہ تعالیٰ
فرماتا ہے کہ میں نے جنت بطور ماوی مقدر کر دی ہے اور اسے جنت الفردوس میں سکونت عطا
کروں گا اور ہر روز ستر مرتبہ اسے اپنے دیدار سے مشرف کروں گا.یہاں لفظ سٹر جو ہے اس
کے متعلق بتانا ضروری ہے کہ عربوں میں یہ ایک عدد ہے جو کثرت کی علامت ہے یعنی بکثرت
میں اسے دیدار نصیب کروں گا.تو عرب اسے یوں بھی بیان کرتے ہیں کہ ستر مرتبہ.تو اس سے
مراد ظاہری طور پر 70 نہیں ہے.بعض تو ان جنتوں میں ایسے بھی ہوں گے جیسے حضرت
محمد مصطفی علی یکم جو ہمیشہ دیدار کی حالت میں ہی رہیں گے اور ساتھ ہی یہ جو نسخہ آپ کے سامنے
پیش کیا گیا ہے اس کو آنحضور علی ایم نے فراخی رزق کا نسخہ بھی بیان فرمایا ہے.پس وہ لوگ جو مختلف قسم کی تنگیوں میں مبتلا ہوتے ہیں ان کو اسی ترتیب سے یہ دعا کرنی
چاہئے جس کا آخری ٹکڑا یہ ہے.وَ تَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ تو ان سب دعاؤں سے
گزرنے کے بعد جب آپ وَ تَرْزُقُ مَن نَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ تک پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ
کی اس دعا کو باقی سب دعاؤں کی برکت سے بھی قبول فرمالے گا اور آپ کے رزق میں فراخی
عطا فرمائے گا.خطبہ جمعہ حضرت خلیفہ المسیح الرابع ، فرمودہ 12 / اپریل 1991ء - خطبات طاہر جلد 10 صفحہ 321 -323)
472
Page 481
XXXXXXXXXXXXXXX
سورة آل عمران - آیات 191 تا 195
XXXXX
اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوتِ وَالْأَرْضِ 191.آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات
اور دن کے آگے پیچھے آنے میں عقل مندوں کے
وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَايَتٍ لِأُولِى
الْأَلْبَابِ
لئے یقیناً کئی نشان ( موجود ) ہیں.الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيْمًا وَقُعُودًا وَ عَلى 192 - ( وہ عقل مند ) جو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے
جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوتِ
وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلا
سُبْحَنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ
پہلوؤں پر اللہ کو یاد کرتے ( رہتے ) ہیں اور آسمانوں
اور زمین کی پیدائش کے بارے میں غور وفکر سے کام
لیتے ہیں ( اور کہتے ہیں کہ ) اے ہمارے رب تو نے
اس (عالم) کو بے فائدہ نہیں پیدا کیا.تو (ایسے
بے مقصد کام کرنے سے) پاک ہے.پس تو ہمیں
آگ کے عذاب سے بچا (اور ہماری زندگی کو
بے مقصد بننے سے بچالے ).رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ 193.اے ہمارے رب! جسے تو آگ میں داخل کرے
گا اسے تو تو نے یقیناً ذلیل کر دیا.اور ظالموں کا کوئی
اخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ
( بھی ) مدد گار نہیں ہوگا.رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيَّا يُنَادِى لِلْإِيْمَانِ 194.اے ہمارے رب! ہم نے یقیناً ایک ایسے
آنْ أَمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَأَمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا
ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ
الْأَبْرَارِ
پکارنے والے کی آواز جو ایمان ( دینے) کے لئے
بلاتا ہے ( اور کہتا ہے ) کہ اپنے ربّ پر ایمان لاؤ
ئنی ہے.پس ہم ایمان لے آئے.اس لئے اے
ہمارے رب! تو ہمارے قصور معاف کر اور ہماری
بدیاں ہم سے مٹادے اور ہمیں نیکوں کے ساتھ ( ملا
کر ) وفات دے.473
Page 482
رَبَّنَا وَاتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا 195 - ( اور ) اے ہمارے رب! ہمیں وہ (کچھ)
تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيِّمَةِ ۖ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ
الْمِيعَادَة
دے جس کا تُو نے اپنے رسولوں ( کی زبان ) پر ہم سے
وعدہ کیا ہے اور قیامت کے دن ہمیں ذلیل نہ کرنا.تو
اپنے وعدہ کے خلاف ہر گز نہیں کرتا.474
Page 483
إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوتِ وَ الْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَأَيْت
الأولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ فِيهَا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَ
يَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا
سُبْحَنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ
(ال عمران (192-191)
حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں:
یعنی آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات دن کے اختلاف میں دانشمندوں کے لئے
صانع عالم کی ہستی اور قدرت پر کئی نشان ہیں.دانشمند وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو خدا کو بیٹھے،
کھڑے اور پہلو پر پڑے ہونے کی حالت میں یاد کرتے رہتے ہیں اور زمین اور آسمان اور
دوسری مخلوقات کی پیدائش میں تفکر اور تدبر کرتے رہتے ہیں اور ان کے دل اور زبان پر یہ
مناجات جاری رہتی ہے کہ اے ہمارے خداوند! تو نے ان چیزوں میں سے کسی چیز کو عبث اور
بیہودہ طور پر پیدا نہیں کیا بلکہ ہر یک چیز تیری مخلوقات میں سے عجائبات قدرت اور حکمت سے
بھری ہوئی ہے کہ جو تیری ذات بابرکات پر دلالت کرتی ہے.( براہین احمدیہ، روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 306-305 حاشیہ نمبر 11)
رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ یعنی جب دانشمند اور اہل عقل
انسان زمین اور آسمان کے اجرام کی بناوٹ میں غور کرتے اور رات اور دن کی کمی بیشی کے
موجبات اور علل کو نظر عمیق سے دیکھتے ہیں انہیں اس نظام پر نظر ڈالنے سے خدا تعالیٰ کے وجود
پر دلیل ملتی ہے.پس وہ زیادہ انکشاف کے لئے خدا سے مدد چاہتے ہیں اور اس کو کھڑے ہو کر
اور بیٹھ کر اور کروٹ پر لیٹ کر یاد کرتے ہیں جس سے ان کی عقلیں بہت صاف ہو جاتی ہیں.پس جب وہ ان عقلوں کے ذریعہ سے اجرام فلکی اور زمینی کی بناوٹ احسن اور اولی میں فکر کرتے
475
Page 484
ہیں تو بے اختیار بول اٹھتے ہیں کہ ایسا نظام ابلغ اور محکم ہر گز باطل اور بے سود نہیں بلکہ صانع
حقیقی کا چہرہ دکھلا رہا ہے.پس وہ الوہیت صانع عالم کا اقرار کر کے یہ مناجات کرتے ہیں یا
الہی تو اس سے پاک ہے کہ کوئی تیرے وجود سے انکار کر کے نالائق صفتوں سے تجھے موصوف
کرے.سو تو ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا.یعنی تجھ سے انکار کرنا عین دوزخ ہے اور تمام
آرام اور راحت تجھ میں اور تیری شناخت میں ہے.جو شخص کہ تیری سچی شناخت سے محروم رہاوہ
در حقیقت اسی دنیا میں آگ میں ہے.اسلامی اصول کی فلاسفی، روحانی خزائن جلد 10 صفحہ 434)
حمد اہل اسلام وہ قوم ہے جن کو جابجا قرآن میں یہی رغبت دی گئی ہے کہ وہ فکر اور خوض
میں مشق کریں اور جو کچھ عجائبات صنعت زمین و آسمان میں بھرے پڑے ہیں ان سے واقفیت
حاصل کریں.مومنوں کی تعریف میں خدائے تعالیٰ فرماتا ہے.يَذْكُرُونَ
اللَّهَ قِمَّا وَقُعُودًا و
عَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا مومن وہ
لوگ ہیں جو خدائے تعالیٰ کو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے بستروں پر لیٹے ہوئے یاد کرتے ہیں اور
جو کچھ زمین و آسمان میں عجائب صنعتیں موجود ہیں ان میں فکر اور غور کرتے رہتے ہیں اور جب
لطائف صنعت الہی ان پر کھلتے ہیں تو کہتے ہیں کہ خدایا تو نے ان صنعتوں کو بیکار پیدا نہیں کیا
یعنی وہ لوگ جو مومن خاص ہیں صنعت شناسی اور ہیئت دانی سے دنیا پرست لوگوں کی طرح
صرف اتنی ہی غرض نہیں رکھتے کہ مثلاً اسی پر کفایت کریں کہ زمین کی شکل یہ ہے اور اس کا قطر
اس قدر ہے اور اس کی کشش کی کیفیت یہ ہے اور آفتاب اور ماہتاب اور ستاروں سے اس کو
اس قسم کے تعلقات ہیں بلکہ وہ صنعت کی کمالیت شناخت کرنے کے بعد اور اس کے خواص
کھلنے کے پیچھے صانع کی طرف رجوع کر جاتے ہیں اور اپنے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں.سرمه چشم آریہ، روحانی خزائن جلد 2 صفحہ 191 تا 192 )
آسمانوں کی بناوٹ اور زمین کی بناوٹ اور رات اور دن کا آگے پیچھے آنا دانشمندوں کو
اس اللہ کا صاف پتا دیتے ہیں جس کی طرف مذہب اسلام دعوت کرتا ہے.اس آیت میں کس
476
Page 485
قدر صاف حکم ہے کہ دانشمند اپنی دانشوں اور مغزوں سے بھی کام لیں اور جان لیں کہ اسلام کا خدا
ایسا گورکھ دھندا نہیں کہ اسے عقل پر پتھر مار کر بجبر منوایا جائے اور صحیفہ فطرت میں کوئی بھی
ثبوت اس کے لیے نہ ہو بلکہ فطرت کے وسیع اوراق میں اس کے اس قدر نشانات ہیں جو صاف
بتلاتے ہیں کہ وہ ہے.ایک ایک چیز اس کا ئنات میں اس نشان اور تختہ کی طرح ہے جو ہر
سڑک یا گلی کے سر پر اس سڑک یا محلہ یا شہر کا نام معلوم کرنے کے لیے لگائے جاتے ہیں.خدا کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور اس موجود ہستی کا پتہ ہی نہیں بلکہ مطمئن کر دینے والا ثبوت
دیتی ہے زمین و آسمان کی شہادتیں کسی مصنوعی اور بناوٹی خدا کی ہستی کا ثبوت نہیں دیتیں بلکہ
اس خدائے أحد الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدُ کی ہستی کو دکھاتی ہیں جو زندہ اور قائم خدا ہے اور
جسے اسلام پیش کرتا ہے.طبعی تحقیقا تیں جہاں تک ہوتی چلی جائیں گی وہاں تو حید ہی توحید نکلتی چلی جائے گی.اللہ تعالیٰ اس آیت إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوتِ وَالْأَرْضِ الآیۃ میں بتلاتا ہے کہ جس خدا کو قرآن
پیش کرتا ہے اس کے لیے زمین آسمان دلائل سے بھرے پڑے ہیں.رپورٹ جلسہ سالانہ 1897 ، صفحہ 70 تا 71)
رپورٹ جلسہ سالانہ 1897 ، صفحہ 71)
قرآن کریم میں ان لوگوں کو جو عقل سے کام لیتے ہیں اولوالالباب فرمایا ہے.پھر اس
کےآگےفرماتا ہے: الَّذِيْنَ يَذْكُرُونَ
اللَّهَ قِمَّا وَقُعُودًا وَ عَلَى جُنُوبِهِمُ الآية ـ اس آیت
میں اللہ تعالیٰ نے دوسرا پہلو بیان کیا ہے کہ اولوالالباب اور عقل سلیم بھی وہی رکھتے ہیں جو اللہ
جل شانہ کا ذکر اٹھتے بیٹھتے کرتے ہیں.یہ گمان نہ کرنا چاہیے کہ عقل و دانش ایسی چیزیں ہیں
جو یونہی حاصل ہوسکتی ہیں، نہیں! بلکہ سچی فراست اور سچی دانش اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیے
بغیر حاصل ہی نہیں ہوسکتی.اسی واسطے تو کہا گیا ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ نورِ
الہی سے دیکھتا ہے.صحیح فراست اور حقیقی دانش جیسا میں نے ابھی کہا کبھی نصیب نہیں ہو سکتی
جب تک تقویٰ میسر نہ ہوا گرتم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو عقل سے کام لو، فکر کرو،سوچو، تدبر اورفکر
477
Page 486
کے لیے قرآن کریم میں بار بار تا کید میں موجود ہیں.کتاب مکنون اور قرآن کریم میں فکر کرو اور
پارس طبع ہو جاؤ.جب تمہارے دل پاک ہو جائیں گے اور ادھر عقل سلیم سے کام لو گے اور
تقویٰ کی راہوں پر قدم مارو گے.پھر ان دونوں کے جوڑ سے وہ حالت پیدا ہو جائے گی کہ
رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاً سُبْحَنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ تمہارے دل سے نکلے گا.اس وقت
سمجھ میں آجائے گا کہ یہ مخلوق عبث نہیں بلکہ صانع حقیقی کی حقانیت اور اثبات پر دلالت کرتی
ہے تا کہ طرح طرح کے علوم وفنون جودین کو مدددیتے ہیں ظاہر ہوں.رپورٹ جلسہ سالانہ 1897ء، صفحہ 72 تا 73)
رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيْمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ
فَأَمَنَارَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَ كَفِّرْ عَنَّا سَيَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ
(ال عمران: 194)
اے ہمارے خدا! ہم نے ایک منادی کی آوازسنی کہ جولوگوں کو ایمان کی طرف بلاتا ہے.تریاق القلوب، روحانی خزائن جلد 15 صفحه 262)
اے ہمارے پروردگار ! ہم نے پکارنے والے کوسنا.خطبہ الہامیہ، روحانی خزائن جلد 16 صفحه 138)
اے ہمارے خدا! ہم نے ایک آواز دینے والے کی آواز کوسنا جو کہتا تھا کہ اپنے ایمان
کو درست کرو اور قومی کرو.( نزول المسیح ، روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 502)
فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ الى لا أضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ
أَلْقَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأَخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَ
اُوْذُوا فِي سَبِيلِي وَ قُتَلُوا وَ قُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيَاتِهِمْ
وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهرُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللهِ وَاللهُ
عندها حُسنُ القَوَابِ (آل عمران : 196)
478
Page 487
میں تم میں سے کسی عامل کا عمل ضائع نہیں کروں گا خواہ وہ مرد ہو خواہ عورت ہو.حضرت
خلیفہ امسیح الثالث رحمہ اللہ فرماتے ہیں :
( شہادت القرآن، روحانی خزائن جلد 6 صفحه 331)
پہلی بات ان آیات سے ہمیں یہ پتا لگتی ہے کہ آسمان اور زمین کی پیدائش یعنی کائنات
کی ہر شے ایک آیت ایک نشان ہے.ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں پتا بتاتی ہے حقائق کا.جو
ہمیں پتا دیتی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات اور اس کی عظمت اور اس کے جلال اور
اس کی قدرت کا.ہر چیز ہماری راہنمائی کر رہی ہے ہمارے پیدا کرنے والے رب کی طرف
اور صرف مادی اشیاء ہی نہیں بلکہ اس کا ئنات کو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے دوحصوں میں تقسیم
کیا.ایک تو مادی اشیاء ہیں جن کو آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش سے تعبیر کیا گیا ہے اور
دوسرے زمانہ ہے اور اس کو وَ اخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ سے تعبیر کیا گیا ہے.زمانہ اپنے اثرات دکھاتا ہے ان جہانوں میں اور زمانہ سے پیدا ہونے والا ہر اثر ہمیں کوئی
سبق دے رہا ہے.ہمیں کچھ سکھاتا ہے ہماری رہنمائی اور رہبری کرنے والا ہے تو یہاں یہ
فرمایا کہ یہ کائنات جو ہے اس کے ہر دو حصے مادی حصہ بھی اور زمانہ بھی جو اپنی ذات میں ایک
حقیقت ہے.زمانے کے اثرات مادی دنیا پر ہوتے ہیں مثلاً ان کا بڑا اور چھوٹا ہونا ہماری
فصلوں پر اثر انداز ہوتا ہے.بعض ایسے پودے ہیں جن کے لئے دنوں کا چھوٹا رہنا ضروری
ہے.بعض ایسے پودے ہیں جن کے لئے چھوٹے دنوں کا اور لمبی راتوں کا ہونا ضروری ہے.بعض ایسے پودے ہیں جن کے لئے لمبے دنوں کا اور چھوٹی راتوں کا ہونا ضروری ہے.بعض
ایسے پودے ہیں جن کیلئے سورج کی روشنی اور اندھیرے کی ایک جیسی لمبائی کا ہونا ضروری ہے.تو یہ زمانہ سے تعلق رکھتا ہے.زمانہ ہر آن حرکت میں ہے اور فاصلے کی نسبتوں کو قائم کرنے
والا ہے.کس قدر تیزی سے کوئی چیز چل رہی ہے یا کتنی دور ہے کوئی چیز.اس وقت اختصار
کے ساتھ زمانہ کے متعلق اس حقیقت کو بیان کر دینا کافی ہے.479
Page 488
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کو ہم نے دو طاقتیں دی ہیں ایک ذکر کی اور ایک تفکر کی اور
جو عقل مند ہیں خالص اور صحیح عقل رکھنے والے عقل اور ٹب میں یہ فرق ہے.عقل میں جب
ہوائے نفس شامل ہو جائے اور وہ خالص نہ رہے تب بھی عربی زبان اسے عقل ہی کہتی ہے مثلاً
آج کی مہذب دنیا جو دنیا میں ڈوب گئی اور خدا کو بھول گئی وہ بھی عربی زبان کے لحاظ سے عقلمند
کہلائیں گے اگر چہ ان کی عقل میں ان کی ادنی خواہشات اور میلان نفس کی بھی بڑی ملاوٹ
آگئی اور انہوں نے اپنی تسلی کے لئے گراوٹوں میں لذتیں محسوس کرنی شروع کر دیں اور اس کا
جواز پیدا کرلیا اور اس حد تک چلے گئے یہ عقلمند کہ انگلستان کی ملکہ کو سڈومی (Sodomy) بل
پر دستخط کرنے پر بھی مجبور ہونا پڑا.اس حد تک گراوٹ اور عقلمند بھی ہیں عربی زبان ان کے لئے
عقل کا لفظ استعمال کرے گی لیکن عربی زبان ان کے لئے اُولُوا الْأَلْبَابِ کا لفظ نہیں استعمال
کرے گی.اس واسطے کہ کب کے معنے ہیں خالص عقل جو اپنی صفائی میں
اور پیورٹی (Purity) میں انتہا کو پہنچ چکی ہو اس کو عربی زبان میں کب کہتے ہیں تو یہاں اللہ
تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو خالص عقل دی تھی.اس نے اس کو اپنی نالائقیوں کی وجہ
سے اور گری ہوئی خواہشات کے نتیجہ میں ناخالص بنادیا اور گدلا کر دیا لیکن وہ لوگ جنہوں نے
خالص عقل کو قائم رکھا وہ اپنی ان دو طاقتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں.ایک ذکر سے ایک تفکر
سے.ذکر وہ کرتے ہیں ہر حالت میں يَذْكُرُونَ الله قيما وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهم اور وہ تقف
بھی کرتے ہیں تفکر بھی وہ ہر حالت میں کرتے ہیں.اس آیت سے یہی واضح ہوتا ہے عربی میں
(جیسا کہ مفسرین نے اس کی وضاحت کی ہے ) ذکر اور تفکر میں فرق ہے وہ کہتے ہیں کہ انسان
دو چیزوں سے مرکب ہے.بدن اور روح سے.بدن سے تعلق رکھنے والی عبودیت کو ذ کر کہتے
ہیں اور قلب اور روح سے تعلق رکھنے والی عبودیت کو تفکر کہتے ہیں اور کامل ذکر وہ ہے جوانسان
کے تمام جوارح اور اعضا سے تعلق رکھتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیا نماز پڑھنے کا اور
نماز کے اندر قیام بھی ہے اور رکوع بھی ہے اور سجدہ بھی ہے اور قعدہ بھی ہے اور زبان کا ذکر
بھی.یہ جسم کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں.روزہ ہے اس کا ہمارے بدن کے ساتھ تعلق ہے.ہم
480
Page 489
اپنے جسم کو بھوکا رکھتے ہیں اور حج جو ہے اس کے جو ظاہری ارکان حج ہیں وہ ہمارے جسم سے
تعلق رکھنے والے ہیں.جس عبودیت کا تعلق بدن سے ہے اس کا نام ذکر ہے يَذْكُرُونَ اللهَ
قيما و قُعُودًا وَ عَلَى جُنُوبِهِمُ اور جس عبودیت کا تعلق قلب اور روح کے ساتھ ہے اس کے
متعلق کہا يَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوتِ وَالْأَرْضِ اور عبودیت کے ہر دو حصے ایک دوسرے
پر اثر انداز ہوتے ہیں یعنی جو ظاہری طور پر مثلاً حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
ہے کہ اگر نماز میں دعا کرتے ہوئے رقت نہ پیدا ہوتو وہ مصنوعی طور پر رقت کی حالت پیدا
کرے.آہستہ آہستہ اس کا دل بھی اس طرف حقیقی رقت کی طرف مائل ہو جائے گا اور جو قلب
کی اور روح کی عبودیت ہے اس کے نتیجہ میں جسم جو ہے وہ بھی دل اور روح کے ساتھ خدا تعالیٰ
کے سامنے جھکتا ہے اور اخلاص کے نتیجہ میں انسان کا جسم بھی اعمالِ صالحہ بجالاتا ہے جس کا اللہ
تعالی نے اسے حکم دیا ہے.حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ روایت منسوب ہوتی ہے تَفَكُرُ سَاعَةٍ خَيْرُ
من عِبَادَة ستين سنة کہ ایک گھڑی کا تفکر ساٹھ سال کی عبادت ظاہری سے زیادہ بہتر
ہے.ظاہر ہے کہ عِبَادَة ستين سنةً یہاں اس عبادت کا ذکر ہے جس میں تفکر نہیں.قلب
اور روح کا حصہ نہیں.یعنی جس عبادت میں ہمارا دل شامل نہیں ہوا صرف ظاہر ہے، جس
عبادت میں ہماری روح پکھل کے آستانہ الہی پر نہیں یہ بھی محض نمائش ہے اور ریا ہے.آپ کو
سمجھانے کے لئے ستين سنة کہہ دیا.یعنی بلوغت کی ساری عمر کی کھوکھلی عبادت سے بھی
زیادہ ہے کیونکہ وہ چھلکا ہے وہ تو کھوکھلی چیز ہے اس کے اندر تو کوئی حقیقت نہیں، کوئی
اخلاص نہیں.خدا تعالیٰ کے لئے کوئی پیار اور محبت نہیں ، اس محبت کے نتیجہ میں خدا تعالیٰ پر
قربان ہونے کی کوئی خواہش نہیں.خدا تعالیٰ کے لئے ہر چیز کو چھوڑ دینے کا کوئی عزم نہیں.وہ عبادت تو خدا تعالیٰ قبول نہیں کرے گا.ان آیات کے بعد دعا کی تعلیم دی اور اس میں یہ ہمیں بتایا گیا کہ دعا کی قبولیت کے لئے
کوئی وسیلہ ہونا چاہیے.یعنی کوئی ایسی شکل ہونی چاہئے کہ دعا قبول ہو جائے.ایسی دعا جو
481
Page 490
استحقاق پیدا کر رہی ہو خدا تعالیٰ کی نگاہ میں قبولیت کا اور یہاں جو پہلے بیان ہوا ہے وہ یہی ہے
کہ ذکر اور فکر ہر دو سے تعلق رکھنے والی عبودیت کے جو تقاضے ہیں جب وہ پورے کئے جائیں
تب دعا قبول ہوتی ہے.اگر ایک شخص ساری رات جاگ کے دعا کرے اور ہر رات جاگ رہا
ہوا اپنی زندگی میں لیکن عمل نہ کرے خدا تعالیٰ کے احکام پر اس کی دعا قبول نہیں ہوگی.دعا کی قبولیت کے لئے شرائط بیان کی گئی ہیں ان آیات میں اور یہی چیز میں اس وقت آپ
کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں.بیان کی گئی ہیں یہ شرائط شروع میں بھی اور پھر آخر میں بھی.پہلے تو یہ کہا کہ ذکر کرنے والے اور تفکر کرنے والے جو ہیں وہ جسم کے لحاظ سے، بدن کے لحاظ
سے بھی عبودیت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں اور قلب وروح کے لحاظ سے بھی عبودیت کے
تقاضوں کو پورا کرنے والے ہیں اور یہاں جو ذ کر اور فکر تھا اس کی روح یہ ہے کہ ہر وقت خدا
کے ذکر میں مشغول رہنا اور خدا تعالیٰ کی جو مصنوعات ہیں جو خلق ہے اس سے دل کا ، ذہن کا،
روح کا صحیح استدلال قائم کرنا کیونکہ ہر چیز خدا تعالیٰ کی طرف پوائنٹ (Point) کررہی ہے.ایک نشان ہے جس طرح سڑکوں پر نشان ہوتا ہے.یہ راستہ جاتا ہے لاہور کی طرف.“
خدا تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ہر شے جو ہے وہ نشان ہے کہ یہ راستہ جاتا ہے خدا کو پہچاننے
عرفان اور معرفتِ الہی کی طرف اور ذکر کرنا تفکر فی مصنوعات کرنار بوبیتِ خداوندی کا اعتراف
کرنا یہ شرائط قبولیت دعا ہیں.ذکر اللہ میں ہمیشہ مشغول رہنا.دل اور دماغ اور روح کے ساتھ
تفکر کرنا یعنی معرفت حاصل کر کے اور معرفت اور اس عرفان کا احساس دل اور روح میں بیدار
رہنا.معرفت یہ نہیں ہے کہ کوئی چیز ملی اور جیب میں رکھ لی.معرفت تو ایک احساس ہے جو
روح میں پیدا ہوتا ہے جو احساس ہمیں یہ بتاتا ہے کہ خدا تعالی بڑی عظمتوں والا خدا تعالیٰ
بڑے جلال والا، خدا تعالی بڑے حسن والا نُورُ السّمواتِ وَالْأَرْضِ ہے.ہر چیز پر وہ قادر
ہے.کوئی چیز اس کے سامنے آن ہوئی نہیں.وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے کوئی دنیا کی طاقت اس
کے منصوبوں
کو نا کام نہیں کرسکتی.وہ تمام صفات باری جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنی
بیان کی ہیں ان سب کو اپنے ذہن میں، اپنے دل میں، اپنے مائنڈ ( Mind ) میں، قلب میں
482
Page 491
حاضر رکھنا اور روح کا اس احساس سے لذت حاصل کرنا یہ ہیں شرائط قبولیت دعا.تو ربوبیتِ خداوندی کا اعتراف کرتے ہوئے اس کی حمد و ثنا میں مشغول رہنا اور اس یقین پر
قائم ہونا کہ خدا تعالیٰ کا کوئی فعل عبث اور باطل نہیں ہے.بے حکمت نہیں ہے.مصلحتوں
سے خالی نہیں ہے.ہر چیز جو اس نے پیدا کی وہ کسی مصلحت کے نتیجہ میں پیدا کی اور انسان کو
بھی اس نے کسی مصلحت کے لئے پیدا کیا جس کا ذکر قرآن کریم نے یہ کہہ کے کیا ہے کہ میں
نے اس لئے پیدا کیا ہے اے انسان تجھے کہ تو خدا تعالیٰ کا عبد بننے کی کوشش کرے اور اپنی
تمام طاقتوں پر اس کا رنگ چڑہا کے اس کے حسن میں سے حصہ لے جو تیرے دل نے اور تیری
روح نے خدا کے وجود میں دیکھا اور مشاہدہ کیا اور پھر شرط لگائی ہجرت کی اور مجبور کر کے وطن
سے بے وطن کئے جانے کی.اس کے ایک ظاہری معنی ہیں ایک صوفیا نے معنی کئے ہیں اور
انہوں نے یہ معنی کئے ہیں کہ اپنے نفس سے دوری یعنی اپنے نفس کی خواہشات کو پورا نہ کرنا اپنے
نفس کا ایک وطن ہے اس کی عادتیں ہیں جہاں وہ خوشی محسوس کرتا ہے.ان کو چھوڑ نا خدا کے
لئے بے نفس ہو جانا جن چیزوں سے محبت اور پیار ہے ان کو ترک کر دینا.خدا تعالیٰ کے لئے
ایڈا کو برداشت کرنا اور ایذا کو ایذا نہ سمجھنا اور جو شیطانی وساوس کی یلغار ہو انسان پر اس کے
خلاف جنگ لڑنا ، دفاعی جنگیں کرنا.پس صوفیا اس کے یہ معنے کرتے ہیں کہ شیطانی وسوسوں کے خلاف جنگ کرنا کامیابی کے
ساتھ اور شیطان کو کسی صورت میں یہ اجازت نہ دینا کہ وہ جسے خدا نے اپنا بندہ بنانے کے لئے پیدا
کیا ہے.اسے شیطان اپنا بندہ بنادے اور خدا کی راہ میں قربان ہوجانا شہادت پانا اور ہر چیز قربان
کر کے بھی خدا تعالیٰ کی ناراضگی مول نہ لینے کے سامان پیدا کرنا.یعنی یہ نہ برداشت کرنا کہ خدا
ناراض ہو جائے.دنیا جائے ، رشتہ دار جائیں، تعلقات ٹوٹیں اپنے بیگانے ہوجائیں، جو ہو سو ہولیکن
انسان خدا تعالیٰ کے لئے اپنے نفس پر ایک موت وارد کرے.صوفیا اس کو شہادت کہتے ہیں اور
ظاہری طور پر بھی پھر بسا اوقات بعض لوگوں کو خدا کے حضور جان پیش کرنی پڑ جاتی ہے.تو یہ دس شرائط یہاں قبولیت دعا کی بیان ہوئی ہیں جن کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں دعا
483
Page 492
کی قبولیت کا حق (اسی کے کہنے پر ) پیدا کر لیتی ہے ورنہ انسان کا کوئی حق نہیں خدا پر.لیکن
خدا کہتا ہے اگر یہ دس باتیں تم اپنے اندر پیدا کرو گے تو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا.ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ.اس کا یہ مطلب نہیں کہ سارا دن خدا کو بھولے رہو.ساری راتیں اپنی
غفلت میں بسر کرو اور پانچ منٹ خدا کے حضور دعا کرو اور مجھو کہ خدا پر قرض ہو گیا کہ خدا تمہاری
دعاؤں کو قبول کرے.اسے تمہاری حاجت نہیں تمہیں خدا کی حاجت ہے.سارے کا سارا خدا
کا ہو جانا جسمانی لحاظ سے بھی ، قلبی اور روحانی لحاظ سے بھی اور جیسا کہ ابھی میں نے بتایا ذکر اللہ
میں مشغول رہنا قلب وروح کا مصنوعات باری میں تفکر کرنے کے بعد صحیح نتائج نکالنا، ربوبیت
خداوندی کا اعتراف کرتے ہوئے حمد و ثنا میں مشغول رہنا، اللہ تعالیٰ کو ہر ایسی چیز سے پاک
سمجھنا جو اس کی طرف عبث اور باطل چیز کو منسوب کرنے والی ہو، تا اس کی راہ میں ہجرت کرنا،
بے وطنی کو قبول کرنا، ہر قسم کی اندرونی اور بیرونی ایڈا کو برداشت کرنا، شیطانی حملوں کا کامیاب
مقابلہ کرنا اور فنا کی حالت اپنے پر طاری کر لینا.خدا کہتا ہے میں ایسے بندوں کی دعائیں اپنے
فضل سے سنتا ہوں اور قبول کرتا ہوں.کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی بات
منوائے.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خدا کے فضل سے ہی انسان جنت میں
جاتا ہے اپنے کسی عمل سے نہیں.یہاں بھی خدا تعالیٰ نے جب دعا قبول کر کے ثواب دینے کا
ذکر ہوا ہے تو وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهرُ (آل عمران:196) فرمایا کہ
میرے فضل سے جنتیں مل گئیں خدا کی رضا کی.یہ نہیں کہا تم نے دس شرائط پوری کیں اس لئے
اس نے جنت میں بھیج دیا.یہ کہا ہے ثَوَابًا مِّنْ عِندِ اللہ یہ بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے ثواب
ہے.تمہارے اپنے عمل کا نتیجہ پھر بھی وہ نہیں ہوگا.لیکن تم اس قابل ہو جاؤ گے کہ خدا تعالیٰ اگر
چاہے تو تم سے پیار کرے.باقی جو خود ناپاک بنتا ہے خدا تعالیٰ جو پاکوں کا پاک ہے.اس ناپاک سے کیسے پیار
کرنے لگ جائے گا.اس کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا لیکن ثُوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللهِ ہے یعنی دس
ا
شرائط پوری کرنے کے بعد دعا کا قبول ہونا اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہونا وہ بھی انسان کے
484
Page 493
کسی اپنے فعل کے نتیجہ میں نہیں بلکہ محض ثوابا من عِنْدِ اللہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب
ہے جو اسے مل رہا ہے.اللہ تعالیٰ ہمیں اس حقیقت زندگی کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے اور ہم
جیسے بھی ہیں کمزور و ناتواں اور غافل ہمیں توفیق دے کہ وہ ہم سے پیار کرنے لگ جائے اور
جب ہم پر اس کا فضل ہو تو شیطان ہمارے دل میں اس وقت بھی یہ وسوسہ نہ پیدا کرے کہ گویا ہم
یہ سمجھیں کہ خدا تعالیٰ کا پیار ہمیں اس لئے ملا کہ خدا تعالیٰ نے یہ چاہا کہ ہم پر فضل کرے اور ہم
سے پیار کرے ورنہ نالائق مزدوروں سے زیادہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے خدا کے حضور.اللہ
تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا کرے.( خطبات ناصر جلد ہشتم صفحه 107 تا114 انوار القرآن تفسیر حضرت خلیفہ المسیح الثالث جلد اول صفحہ 536-541)
حضرت خلیفة المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز فرماتے ہیں:
عطا رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عائشہ کی خدمت میں میں،
ابن عمرؓ اور عبید اللہ بن عمر کے ساتھ گئے اور ہم نے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی
عجیب ترین بات بتائیں جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھی ہو.اس پر حضرت
عائشہ آپ کی یاد میں بیتاب ہو کر رو پڑیں اور کہنے لگیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہر ادا
ہی نرالی تھی.پھر فرمانے لگیں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات
میرے پاس تشریف لائے اور لیٹے بستر پر.پھر آپ نے فرمایا اے عائشہ ! کیا آج کی رات
تو مجھے اجازت دیتی ہے کہ اپنے رب کی عبادت کرلوں.میں نے کہا خدا کی قسم مجھے تو آپ کی
خواہش کا احترام ہے اور آپ کا قرب پسند ہے.میری طرف سے آپ کو اجازت ہے.تب
آپ اٹھے.مشکیزہ سے وضو کیا اور نماز کیلئے کھڑے ہوئے اور نماز پڑھنی شروع کی اور اس قدر
روئے کہ آنسو آپ کے سینے پر گرنے لگے اور نماز کے بعد دائیں طرف ٹھیک لگا کر اس طرح
بیٹھ گئے کہ آپ کا دایاں ہاتھ آپ کی دائیں رخسار کے نیچے تھا.پھر رونا شروع کر دیا یہاں
تک کہ آپ کے آنسو زمین پر ٹپکنے لگے.فجر کی نماز کے وقت حضرت بلال بلانے کیلئے آپ
485
Page 494
کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آپ کو اس طرح گریہ وزاری کرتے ہوئے دیکھا تو
کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ! آپ اتنا کیوں روتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ آپ کے گزشتہ اور آئندہ
ہونے والے سارے گناہ بخش چکا ہے.اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا.کیا ئیں
اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں.اور میں کیوں نہ روؤں کہ آج رات میرے رب نے یہ آیات نازل
کی ہیں.وہ آیات ہیں آل عمران کی.اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ
وَالنَّهَارِ لايت لأولى الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِمَّا وَقَعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمُ
وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحْنَكَ فَقِنَا
عَذَابَ النَّار (آل عمران: 191-192) یعنی یقیناً آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، رات اور دن
کے ادلنے بدلنے میں صاحب عقل لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں.اور اے ہمارے رب تو ہمیں
آگ کے عذاب سے بھی بچانا.پھر دوسری روایت میں اس کا ذکر اس طرح ملتا ہے کہ حضرت عائشہ نے دریافت کیا کہ
یا رسول اللہ ! آپ کو اتنا رونا کیوں آرہا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے گزشتہ اور آئندہ ہونے
والے گناہ بخش دیتے ہیں.اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ئیں اللہ کا شکر گزار
بندہ نہ بنوں.اور میں ایسا کیوں نہ کروں جبکہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اس رات اپنی یہ آیات نازل
فرمائی ہیں إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَأَيْتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ
الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِمَّا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوتِ
وَالْأَرْضِ.رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ...السد العالی فرمود یا اپریل 2010 ، خطبات مسرور جلو و مار 19 (20)
حضرت خلیفۃ اسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز فرماتے ہیں:
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنی رحمانیت کے نظارے دکھاتے ہوئے تمہارے
لئے یہ جو زمین و آسمان پیدا کیا ہے اس پر غور کرو.ستارے ہیں، چاند ہے،سورج ہے، فضا میں
486
Page 495
ا
مختلف قسم کی گیسز ہیں، مختلف قسم کی تہیں ہیں جو بعض اجرام فلکی کے نقصانات سے تمہیں محفوظ
رکھے ہوئے ہیں.ہر ایک چیز اپنے اپنے بتائے ہوئے وقت، رفتار اور دائرے میں گردش کر
رہی ہے.پھر رات اور دن، چاند اور سورج ہماری زمین کی پیدائش پر اثر انداز ہورہے ہیں.یعنی زمین میں جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں، مختلف موسم ہیں، بارش ہے، سردی ہے، گرمی ہے اور
اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے مختلف فصلیں اور پھل، درخت اور پودے مہیا کئے ہوئے
ہیں.باغ وغیرہ ہیں جن سے تم فائدہ اٹھاتے ہو.تو جولوگ ان چیزوں پر غور کرتے ہیں اور اللہ
تعالی کی بڑائی بیان کرتے ہیں، اس پر اس کا شکر ادا کرتے ہیں وہ اس بات پر بھی قائم ہوتے
ہیں کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوتا ہے.اللہ تعالیٰ نے دنیا کے بارہ میں جو بتایا
وہ اگر حق ہے تو آخرت بھی حق ہے.پس یہ سب دیکھ کر ایک مومن دعا کرتا ہے کہ ہماری
غلطیوں کو، کوتاہیوں کو معاف فرما.ان کی وجہ سے ہمیں کسی پکڑ میں نہ لے لینا اور ہمیں آخرت
کے عذاب سے بچا.یہ دعا اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم میں سکھائی ہے.فرماتا ہے الَّذِينَ
يَذْكُرُونَ اللهَ فِيمَا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا
خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاً سُبْحَنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (آل عمران:192) وہ لوگ جو اللہ کو یاد کرتے
ہیں، کھڑے ہوئے بھی اور بیٹھے ہوئے بھی اور اپنے پہلوؤں کے بل بھی اور آسمان وزمین کی
پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں اور بے ساختہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو نے ہرگز یہ
بے مقصد پیدا نہیں کیا.پاک ہے تو پس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا.حضرت مسیح موعود عليه الصلوة والسلام رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَنَكَ فَقِنَا عَذَابَ
النَّارِ کے بارہ میں فرماتے ہیں کہ : یا الہی تو اس سے پاک ہے کہ کوئی تیرے وجود سے
انکار کر کے نالائق صفتوں سے تجھے موصوف کرے.ایسی باتیں تیری طرف منسوب کرے جو مکمل
اور کامل نہیں ہیں جو تیرے مقام سے بہت گری ہوئی چیزیں ہیں.جن میں کمزوریاں، خامیاں اور سقم
ہیں.سو تو ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا.یعنی تجھ سے انکار کرنا عین دوزخ ہے.66
اسلامی اصول کی فلاسفی.روحانی خزائن جلد 10 صفحہ 120)
487
Page 496
فرمایا ” مومن وہ لوگ ہیں جو خدائے تعالیٰ کو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے بستروں پر لیٹے
ا
ہوئے یاد کرتے ہیں اور جو کچھ زمین و آسمان میں عجائب صنعتیں موجود ہیں ان میں فکر اور
غور کرتے رہتے ہیں اور جب لطائف صنعت الہی ان پر کھلتے ہیں“.یعنی اس کائنات کے جو
باریک سے باریک راز ہیں وہ اُن پر کھلتے ہیں جب وہ اللہ تعالی کی پیدا کردہ اشیاء کے نظارے
دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ خدایا تو نے ان صنعتوں کو بے کار پیدا نہیں کیا.یعنی وہ لوگ جو مومن
خاص ہیں صنعت شناسی اور ہیئت دانی سے دنیا پرست لوگوں کی طرح صرف اتنی ہی غرض نہیں
رکھتے.یعنی اللہ تعالی کی پیدا کردہ اشیاء ہیں ان کو دیکھ کر اور اللہ تعالیٰ نے جو مختلف چیزیں پیدا
کی ہیں ان کی شکلیں دیکھ کر ، آسمان اور زمین میں جو مختلف چیزیں چاند، سورج، ستارے ہیں،
دنیا کی پیدائش ہے، اس کو دیکھ کر فرمایا کہ دنیا پرست لوگوں کی طرح صرف اتنی ہی غرض نہیں
رکھتے کہ مثلاً اسی پر کفایت کریں کہ زمین کی شکل یہ ہے اور اس کا قطر اس قدر ہے اور اس کی
کشش کی کیفیت یہ ہے اور آفتاب اور ماہتاب اور ستاروں سے اس کو اس قسم کے تعلقات
ہیں بلکہ وہ صنعت کی کمالیت شناخت کرنے کے بعد اور اس کے خواص کھلنے کے پیچھے صانع کی
طرف رجوع کر جاتے ہیں.جب ان چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں تو پھر وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے
پیچھے اس کو پیدا کرنے والا کون ہے.اور اپنے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں“.( سرمه چشم آریہ.روحانی خزائن جلد نمبر 2 صفحہ 144-143)
جب اس پیدا کرنے والے کا پتہ لگ جاتا ہے، خدا تعالیٰ کی عظمت کا پتہ لگتا ہے، خدا تعالیٰ
کی قدرتوں
کا پتہ لگتا ہے تو پھر ایمان میں اور مضبوطی پیدا ہوتی ہے، جب یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ
ان سب چیزوں کو پیدا کرنے والا ایک خدا ہے تو اس کی ہستی اور طاقتوں پر اور یقین بڑھتا
ہے.پھر اس بات کا بھی یقین بڑھتا ہے کہ ان سب کو پیدا کرنے والا وہ زندہ خدا ہے جس
نے اپنی عبادت کرنے کے لئے بھی کہا ہے، دعائیں مانگنے کی طرف بھی توجہ دلائی ہے اور عمل
کے حساب سے اچھے اور بُرے اعمال سے بھی آگاہ کیا ہے.تو پھر وہ پکارتا ہے کہ اے اللہ !
488
Page 497
مجھے نیک عملوں کی بھی توفیق عطا فرما تا کہ میں آگ کے عذاب سے بچوں اور تیرے پیار کی نظر
ہمیشہ مجھ پر پڑتی رہے.خطبہ جمعہ حضرت خلیفة المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی فرموده 2 ستمبر 2006ء،خطبات مسرور جلد چہارم صفحہ 484-486)
489
Page 499
XXXXXXXXXXXXX
سورة بنی اسرائیل.آیات 79 تا 85
XXXX
اَقِمِ الصَّلوةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ 79.تو سورج کے ڈھلنے (کے وقت) سے لے کر
الَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ اِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ رات کے خوب تاریک ہو جانے (کے وقت ) تک
( مختلف گھڑیوں میں ) نماز کو عمدگی سے ادا کیا کر.كَانَ مَشْهُودًا
اور صبح کے وقت ( قرآن ) کے پڑھنے کو بھی ( لازم
سمجھ ).صبح کے وقت ( قرآن ) کا پڑھنا یقیناً ( اللہ
کے حضور میں ایک ) مقبول عمل ہے.وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَلَى 80.اور رات کو بھی تو اس (قرآن) کے ذریعہ سے
أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا
کچھ سو لینے کے بعد شب بیداری کیا کر.جو تجھ پر
ایک زائد انعام ہے.(اس طرح پر ) بالکل متوقع
ہے کہ تیرا رب تجھے حمد والے مقام پرکھڑا کر دے.وَقُل رَّبِّ اَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ 81.اور کہہ (کہ) اے میرے رب ! مجھے نیک طور
پر ( دوبارہ مکہ میں ) داخل کر اور ذکر نیک چھوڑنے
واخْرِجُنِى مُخْرَجَ صِدْقٍ وَ اجْعَلْ
تي مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطنًا نَّصِيرًا
والے طریق پر ( مگہ سے) نکال اور اپنے پاس سے
میرا کوئی مددگار ( اور ) گواہ مقرر کر.وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ 82.اور سب لوگوں سے کہہ دے (کہ بس
الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا
اب ) حق آ گیا ہے اور باطل بھاگ گیا ہے
اور باطل تو ہے ہی بھاگ جانے والا.وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ 83.اور ہم قرآن میں آہستہ آہستہ وہ (تعلیم)
لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّلِمِينَ إِلَّا اتار رہے ہیں جو مومنوں کے لئے ( تو ) شفا اور
رحمت ( کا موجب ) ہے اور ظالموں کوصرف خسارہ
خَسَارًا
میں بڑھاتی ہے.491
Page 500
وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ 84.اور جب ہم انسان پر انعام کریں تو وہ
روگردان ہو جاتا ہے اور اپنے پہلو کو (اس
وَنَا بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّكَانَ
يوسان
سے ) دور کر لیتا ہے اور جب اسے تکلیف پہنچے تو
وہ بہت ہی مایوس ہو جاتا ہے.قُل كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ 85.تو (انہیں) کہہ ( کہ ہم میں سے) ہر ایک
أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلان
( فریق) اپنے (اپنے) طریق پر عمل کر رہا ہے پس
اپنے رب پر ہی فیصلہ چھوڑ دو کیونکہ ) تمہارا رب
اسے جو زیادہ صحیح راستہ پر ہے بہتر جانتا ہے (اس لئے
اس کا فیصلہ سچے کی سچائی کو ضرور روشن کر دے گا)
492
Page 501
اقمِ الصَّلوةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ
الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا
(بنی اسرائیل: 79)
حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں:
نماز کیا چیز ہے؟ وہ دعا ہے جو تسی تحمید تقدیس اور استغفار اور درود کے ساتھ تضر، ع
سے مانگی جاتی ہے.سو جب تم نماز پڑھو تو بے خبر لوگوں کی طرح اپنی دعاؤں میں صرف عربی
الفاظ کے پابند نہ رہو کیونکہ ان کی نما ز اور ان کا استغفار سب رسمیں ہیں جن کے ساتھ کوئی حقیقت
نہیں.لیکن تم جب نماز پڑھو تو بجز قرآن کے جو خدا کا کلام ہے اور بجر بعض ادعیہ ماثورہ کے
کہ وہ رسول کا کلام ہے باقی اپنی تمام عام دعاؤں میں اپنی زبان میں ہی الفاظ متضرعا نہ ادا کر لیا
کروتا ہو کہ تمہارے دلوں پر اُس عجز و نیاز کا کچھ اثر ہو.پنجگانہ نمازیں کیا چیز ہیں ؟ وہ تمہارے مختلف حالات کا فوٹو ہے تمہاری زندگی کے لازم
حال پانچ تغیر ہیں جو بلا کے وقت تم پر وارد ہوتے ہیں اور تمہاری فطرت کے لئے اُن کا وارد ہونا
ضروری ہے.(1) پہلے جب کہ تم مطلع کئے جاتے ہو کہ تم پر ایک بلا آنے والی ہے مثلاً جیسے
تمہارے نام عدالت سے ایک وارنٹ جاری ہوا.یہ پہلی حالت ہے جس نے تمہاری تسلی اور
خوشحالی میں خلل ڈالا.سو یہ حالت زوال کے وقت سے مشابہ ہے کیونکہ اس سے تمہاری خوشحالی
میں زوال آنا شروع ہوا اس کے مقابل پر نماز ظہر متعین ہوئی جس کا وقت زوالِ آفتاب سے
شروع ہوتا ہے.(2) دوسرا تغیر اس وقت تم پر آتا ہے جب کہ تم بلا کے محل سے بہت نزدیک کئے جاتے
ہو.مثلاً جب کہ تم بذریعہ وارنٹ گرفتار ہو کر حاکم کے سامنے پیش ہوتے ہو یہ وہ وقت ہے کہ
جب تمہارا خوف سے خون خشک ہو جاتا ہے اور تسلی کا نور تم سے رخصت ہونے کو ہوتا ہے سو یہ
493
Page 502
حالت تمہاری اس وقت سے مشابہ ہے جب کہ آفتاب سے نور کم ہو جاتا ہے اور نظر اس پر جم
سکتی ہے اور صریح نظر آتا ہے کہ اب اس کا غروب نزدیک ہے.اس روحانی حالت کے
مقابل پر نماز عصر مقرر ہوئی.(3) تیسرا تغیر تم پر اس وقت آتا ہے جو اس بلا سے رہائی پانے کی بکلی امید منقطع ہو جاتی
ہے.مثلاً جیسے تمہارے نام فرد قرار داد جرم لکھی جاتی ہے اور مخالفانہ گواہ تمہاری ہلاکت کے
لئے گزر جاتے ہیں یہ وہ وقت ہے کہ جب تمہارے حواس خطا ہو جاتے ہیں اور تم اپنے تئیں
ایک قیدی سمجھنے لگتے ہو.سو یہ حالت اس وقت سے مشابہ ہے جب کہ آفتاب غروب ہو جاتا
ہے اور تمام امیدیں دن کی روشنی کی ختم ہو جاتی ہیں اس روحانی حالت کے مقابل پر نما ز مغرب
مقرر ہے.(4) چوتھا تغیر اس وقت تم پر آتا ہے کہ جب بلاتم پر وارد ہی ہو جاتی ہے اور اس کی سخت
تاریکی تم پر احاطہ کر لیتی ہے مثلاً جب کہ فرد قرار داد جرم اور شہادتوں کے بعد حکم سزا تم کو سنایا
جاتا ہے اور قید کے لئے ایک پولیس مین کے تم حوالہ کئے جاتے ہو سو یہ حالت اس وقت سے
مشابہ ہے جب کہ رات پڑ جاتی ہے اور ایک سخت اندھیرا پڑ جاتا ہے اس روحانی حالت کے
مقابل پر نما ز عشاء مقرر ہے.(5) پھر جب کہ تم ایک مدت تک اس مصیبت کی تاریکی میں بسر کرتے ہو تو پھر آ خر خدا
کا رحم تم پر جوش مارتا ہے اور تمہیں اُس تاریکی سے نجات دیتا ہے.مثلاً جیسے تاریکی کے بعد
پھر آخر کار صبح نکلتی ہے اور پھر وہی روشنی دن کی اپنی چمک کے ساتھ ظاہر ہو جاتی ہے سواس
روحانی حالت کے مقابل پر نماز فجر مقرر ہے اور خدا نے تمہارے فطرتی تغیرات میں پانچ
حالتیں دیکھ کر پانچ نمازیں تمہارے لئے مقرر کیں.اس سے تم سمجھ سکتے ہو کہ یہ نمازیں خاص
تمہارے نفس کے فائدہ کے لئے ہیں.پس اگر تم چاہتے ہو کہ ان بلاؤں سے بچے رہو تو تم
پنجگانہ نمازوں کو ترک نہ کرو کہ وہ تمہاری اندرونی اور روحانی تغیرات کا ظل ہیں.نماز میں
494
Page 503
آنے والی بلاؤں کا علاج ہے تم نہیں جانتے کہ نیا دن چڑھنے والا کس قسم کے قضا و قدر
تمہارے لئے لائے گا پس قبل اس کے جو دن چڑھے تم اپنے مولیٰ کی جناب میں تضرر ع کرو کہ
تمہارے لئے خیر و برکت کا دن چڑھے.“
(کشتی نوح ، روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 68-70)
یا درکھو کہ یہ جو پانچ وقت نماز کے لئے مقرر ہیں یہ کوئی حکم اور جبر کے طور پر نہیں
بلکہ اگر غور کرو تو یہ در اصل روحانی حالتوں کی ایک عکسی تصویر ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ آرقم الصَّلوةَ لِدُلُوكِ الشَّمس یعنی قائم کر نماز کو دُلُوكِ الشَّمس سے.اب دیکھو اللہ
تعالیٰ نے یہاں قیام صلوۃ کو دُلُوكِ الشَّمس سے لیا ہے.دُلُوك کے معنوں میں گو
اختلاف ہے لیکن دو پہر کے ڈھلنے کے وقت کا نام دُلُوك ہے.اب دُلُوك سے لے کر پانچ
نمازیں رکھ دیں اس میں حکمت اور سر کیا ہے.قانون قدرت دکھاتا ہے کہ روحانی تذلل اور
انکسار کے مراتب بھی ڈکوٹ ہی سے شروع ہوتے ہیں اور پانچ ہی حالتیں آتی ہیں.پس یہ طبعی
نما ز بھی اس وقت سے شروع ہوتی ہے جب محزن اور ہم و غم کے آثار شروع ہوتے ہیں.اس
وقت جبکہ انسان پر کوئی آفت یا مصیبت آتی ہے تو کس قدر تذلل اور انکساری کرتا ہے.اب
اس وقت اگر زلزلہ آوے تو تم سمجھ سکتے ہو کہ طبیعت میں کیسی رقت اور انکساری پیدا ہو جاتی ہے.اسی طرح پر سوچو کہ اگر مثلاً کسی شخص پر نایش ہو تو سمن یا وارنٹ آنے پر اس کو معلوم ہوگا کہ
فلاں دفعہ فوجداری یاد یوانی میں نالش ہوتی ہے.اب بعد مطالعہ وارنٹ اس کی حالت میں گویا
نصف النہار کے بعد زوال شروع ہوا.کیونکہ وارنٹ یا سمن تک تو اسے کچھ معلوم نہ تھا.اب
خیال پیدا ہوا کہ خدا جانے ادھر وکیل ہو یا کیا ہو؟ اس
قسم کے ترڈدات اور تفکرات سے جو
زوال پیدا ہوتا ہے یہ وہی حالت ذلوک ہے اور یہ پہلی حالت ہے جو نمازظہر کے قائم مقام
ہے اور اس کی عکسی حالت نماز ظہر ہے.اب دوسری حالت اس پر وہ آتی ہے جبکہ وہ کمرہ
عدالت میں کھڑا ہو.فریق مخالف اور عدالت کی طرف سے سوالات جرح ہورہے ہیں اور وہ
ایک عجیب حالت ہوتی ہے.یہ وہ حالت اور وقت ہے جونمازعصر کا نمونہ ہے کیونکہ عصر گھوٹنے
495
Page 504
اور نچوڑنے کو کہتے ہیں.جب حالت اور بھی نازک ہو جاتی ہے اور فرد قرار داد جرم لگ جاتی
ہے تو یاس اور نا امیدی بڑھتی ہے کیونکہ اب خیال ہوتا ہے کہ سزا مل جاوے گی یہ وہ وقت ہے
جو مغرب
کی نماز کا عکس ہے.پھر جب حکم سنایا گیا اور کنسٹیبل یا کورٹ انسپکٹر کے حوالہ کیا گیا
تو وہ روحانی طور پر نما ز عشاء کی عکسی تصویر ہے.یہاں تک کہ نماز کی صبح صادق ظاہر ہوئی اور
اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ( الم نشرح 7) کی حالت کا وقت آ گیا تو روحانی نماز فجر کا وقت آ گیا
اور فجر کی نما ز اس کی عکسی تصویر ہے.“
رپورٹ جلسہ سالانہ 1897، صفحہ 167،166)
وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا
حمد کئی مقام قرآن شریف میں اشارات و تصریحات سے بیان ہوا ہے کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم مظہر اتم الوہیت ہیں اور ان کا کلام خدا کا کلام اور ان کا ظہور خدا کا ظہور اور ان
کا آنا خدا کا آنا ہے چنانچہ قرآن شریف میں اس بارے میں ایک یہ آیت بھی ہے قُل جَاءَ
الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا - کہ حق آیا اور باطل بھاگ گیا اور باطل
نے بھا گنا ہی تھا.حق سے مراد اس جگہ اللہ جل شانہ اور قرآن شریف اور آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم ہیں.اور باطل سے مراد شیطان اور شیطان کا گروہ اور شیطانی تعلیمیں ہیں.سو دیکھو
اپنے نام میں خدائے تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کیونکر شامل کرلیا اور آنحضرت کا
ظہور فرمانا خدا تعالیٰ کا ظہور فرمانا ہوا ایسا حلالی ظہور جس سے شیطان معہ اپنے تمام لشکروں کے
بھاگ گیا اور اس کی تعلیمیں ذلیل اور حقیر ہوگئیں اور اس کے گروہ کو بڑی بھاری شکست
آئی.اسی جامعیت تامہ کی وجہ سے سورۃ آل عمران جزو تیسری میں مفصل یہ بیان ہے کہ تمام
نبیوں سے عہد واقرار لیا گیا کہ تم پر واجب ولازم ہے کہ عظمت و جلالیت شان خاتم الرسل پر جو
محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ایمان لاؤ اور ان کی اس عظمت اور جلالیت کی اشاعت کرنے
میں بدل و جان مدد کرو.اسی وجہ سے حضرت آدم صفی اللہ سے لے کرتا حضرت مسیح کلمتہ اللہ جس
496
Page 505
قدر نبی و رسول گزرے ہیں وہ سب کے سب عظمت و جلالیت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا
اقرار کرتے آئے ہیں.سرمه چشم آریه، روحانی خزائن جلد 2 صفحہ 277 280 حاشیہ)
كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِه یعنی هر یک شخص اپنی فطرت کے موافق عمل کرتا ہے.( آئینہ کمالات اسلام، روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 289 حاشیہ)
حمد ہر ایک اپنے قومی اور اشکال کے موافق عمل کرنے کی توفیق دیا جاتا ہے.جنگ مقدس ، روحانی خزائن جلد 6 صفحه (279)
ہر شخص اپنے مادہ اور فطرت کے مطابق عمل کر رہا ہے.(ماخوذ از حقائق الفرقان)
حضرت
خلیفہ المسیح الثانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:
(مکتوبات جلد 5 نمبر 5 صفحہ (201)
دُلُوك دَلكَتِ الشَّمْسُ دُلُوا غَرَبَتْ - سورج غروب ہو گیا اصفرت.سورج
زرد ہو گیا.وَقِيلَ مَالَتْ وَزَالَتْ عَنْ كَبِدِا السَّمَاءِ - بعض نے کہا ہے کہ دَلكَتِ الشَّمسُ
کے معنی سورج ڈھلنے کے ہیں (اقرب)
غَسَق: غَسَقَتْ عَيْنُهُ غَسُوْقًا دَمَعَتْ وَقِيلَ انْصَبَّتْ وَقِيلَ أَظْلَبَتْ.اس کی آنکھ
ڈبڈبا آئی.بعض محققین لغت کے نزدیک اس کے معنی آنکھ کے بہنے یا آنکھ پر تاریکی چھا جانے
کے ہوتے ہیں غَسَقَ الَّيْلُ غَسَقَا اشْتَدَّ ظُلمته یعنی رات سخت تاریک
ہوگئی.الْغَسْقُ ظُلْمَةُ أَوَّلِ اللَّيْلِ اَو دَخُولُ أَوَّلِهِ حِينَ يَخْتَلِطُ الظَّلامُ غسق رات کے پہلے
حصے کی تاریکی کو کہتے ہیں یارات کی ابتداء میں تاریکی شروع ہونے کو غسق کہتے ہیں (اقرب)
مَشْهُودًا : یہ شہد سے اسم مفعول کا صیغہ ہے.شھد کا لفظ کسی جگہ پر ظاہر ہونے
اور اس پر اطلاع پانے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے.کہتے ہیں شَهِدَ الْمَجْلِس
شُهُودًا حَضَرَهُ وَاطَّلَعَ عَلَيْهِ کہ وہ مجلس میں حاضر ہوا.اور اس نے اسے دیکھا.شهِدَ اللهُ.آمی
497
Page 506
عَلِمَ اللهُ وقَبَّل الله جب اللہ تعالیٰ کے لئے شہد کا لفظ استعمال ہو تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جانا اور اسے قبول فرمایا - وَقِيلَ كُتب الله.بعض کے نزدیک اس
کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عمل کو لکھ لیا.( اقرب)
ان آیات میں مسلمانوں کو آنے والی خطرناک مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لئے تیار
کیا گیا ہے.ایک طرف ہجرت کے بعد ان قوموں سے مقابلہ ہونے والا تھا.جوظاہر میں
عبادت گزار تھیں.اور مسلمانوں کی سستی انہیں اعتراض کا موقعہ دے سکتی تھی.دوسری طرف
مسلمانوں کو جلد فتوحات ملنے والی تھیں جس سے عبادات میں سستی پیدا ہو جاتی ہے.پس
دونوں امور کوملحوظ رکھتے ہوئے مسلمانوں کو ہوشیار کیا کہ دشمن کے طعن کا نشانہ اسلام کو نہ
بنانا.اور نہ سست ہو کر خدا تعالیٰ کے فضلوں کو کھودینا.حمد اس آیت میں پانچوں نمازوں کے اوقات بتائے گئے ہیں.دُلُوک کے تین معنی ہیں.اور ہر ایک معنی کی رُو سے ایک ایک نماز کا وقت ظاہر کر دیا گیا.( 1 ) مَالَتْ وَزَالَتْ عَنْ كَبِدِ السَّمَاء یعنی زوال کو ڈلوک کہتے ہیں.اس میں ظہر کی نماز
آگئی (2) اضفرت.جب سورج زرد پڑ جائے تو اس کو بھی دلوک کہتے ہیں اس میں نما ز عصر
کا وقت بتادیا گیا.(3) تیسرے معنی غربت یعنی غروب شمس کے ہیں.اس میں نماز مغرب
کا وقت بتایا گیا ہے (4) غَسَقَ الَّيْلُ کے معنی ظُلْمَةُ أَوَّلِ الَّيْلِ کے ہیں.یعنی رات کے
ابتدائی حصہ کی تاریکی.اس میں نما ز عشاء کا وقت مقرر کر دیا گیا.(5) قُرانِ الْفَجْرِ کہہ کر صبح
کی نماز کا ارشاد فرمایا.اس کے سوا کوئی اور تلاوت صبح کے وقت فرض نہیں ہے.إن قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا.احادیث میں آتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا کہ صبح کی نماز کے وقت دن کے فرشتے آتے ہیں اور رات کے فرشتے چلے جاتے
ہیں.وہ فرشتے جب خدا کے پاس جاتے ہیں تو دریافت کرنے پر کہتے ہیں کہ ہم جب دنیا میں
گئے تو تیرے بندوں کو نماز پڑھتے ہی دیکھا اور واپس آئے ہیں تو نماز پڑھتے ہی چھوڑ کر آئے
498
Page 507
ہیں.عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلَّمَ قَالَ تَشْهَدُهُ مَلَائِكَةُ الَّيْلِ
وَمَلَائِكَةُ النّهَارِ (الحدیث) اس کا مطلب یہ ہے کہ صبح کی نماز خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے
سامنے پیش کی جاتی ہے.اور خاص ہی طور سے مقبول ہوتی ہے کیونکہ اس وقت انسان میٹھی نیند
کو چھوڑ کر اٹھتا ہے.صبح کی نماز در اصل عام مسلمان کی تہجد ہی کی نماز ہے.بلاشبہ جو انسان صبح
کی نماز پڑھے گا.اگر اس نے وہ نماز ایمانداری سے پڑھی ہوگی تو باقی نمازیں بھی اس کے
لئے آسان ہو جائیں گی.لسان العرب میں لکھا ہے کہ تجد القَوْم کے معنی لوگوں کے سونے کے بعد نماز
وغیرہ کے لئے بیدار ہونے کے ہیں.نافلة - لفظ نافِلَه نَفَل سے اسم فاعل مؤنث بمعنی مفعول ہے یعنی دی ہوئی
چیز.دیا ہوا انعام - النَّافِلَةُ کے معنى الْغَنِيمَةُ - غنیمت الْعَطِيَّةُ بخشش مَا تَفْعَلُهُ
مما لا يجب - فرض سے زائد عمل کرنا.وَلَد الولد.پوتا.اس کی جمع نوافل آتی ہے.تهجد به میں کی ضمیر قرآن کریم کی طرف پھرتی ہے اور مراد یہ ہے کہ اس نماز میں
تلاوت قرآن پر خاص زور ہونا چاہئے.تہجد کے معنے سو کر اٹھنے کے ہوتے ہیں.اس لئے تہجد کی نماز سے پہلے سونا ضروری
ہے.جولوگ ساری رات جاگنے کے چلے کھینچتے ہیں وہ عبادت نہیں کرتے.شریعت کے منشاء
کو باطل کرتے ہیں.ایسی عبادت قرآن کریم کے منشاء کے خلاف ہے.رسول کریم صلی اللہ
علیہ وسلم ہمیشہ پہلی رات سوتے تھے اور آخر رات میں اٹھ کر تہجد پڑھتے تھے.اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ عبادت کا موقعہ دینا ایک احسان الہی ہے.مگر افسوس
ان لوگوں پر جو نماز کو چھٹی سمجھتے ہیں.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز اپنے رب کی
زیارت ہے.اور زیارت الہی ایک انعام ہے.اور کوئی عقلمند انسان اپنے محبوب کی زیارت کو چٹی
نہیں سمجھے گا.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عبادت کی شان ہی یہ بتائی ہے كَأَنَّكَ تَرَاهُ وَإِنْ لَمْ
499
Page 508
تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ (مسلم جلد اول کتاب الایمان) یعنی صحیح نماز یہ ہے کہ تو خدا تعالیٰ کو دیکھ
لے.یا کم سے
کم نماز کے وقت یہ یقین ہو کہ خدا تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے.پس اتنے بڑے انعام کو
چٹی سمجھنا سخت ظلم ہے نماز اللہ تعالی کے بڑے انعامات میں سے ہے.میرا تو یہ عقیدہ ہے کہ انسان
ایک نماز بھی چھوڑے تو وہ نمازی نہیں کہلا سکتا.کیونکہ حکم اقامة الصلوة کا ہے.اور وہ دوام
کو چاہتا ہے.جب ایک بھی نماز چھوڑ دی گئی ہو تو دوام نہ رہا.كافِلَةٌ لك سے اس بات کا اظہار کیا گیا ہے کہ عبادت کا موقعہ دینا ہمارا ایک احسان ہے.یا ممکن ہے کہ تہجد کی نماز پہلے انبیاء پر واجب نہ کی گئی ہو.اس صورت میں اس کے یہ معنی ہوں
گے کہ یہ عبادت کا موقعہ خاص تیرے لئے انعام ہے.مَقَامًا مَّحْمُودًا میں ایک بہت بڑی پیشگوئی کی گئی ہے.دنیا میں کسی شخص کو بھی اتنی
گالیاں نہیں دی گئیں جتنی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئیں ہیں.ڈاکو، بدکار، بدمعاش، فاسق سے فاسق انسان کو ان گالیوں کے کروڑویں حصہ کے برابر بھی
گالیاں نہیں دی جاتیں جتنی کہ آج تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہیں.مقام محمود عطا
فرما کر اللہ تعالیٰ نے ان گالیوں کا آپ کو صلہ دیا ہے.فرماتا ہے جس طرح دشمن گالیاں دیتا
ہے.ہم مومنوں سے تیرے حق میں درود پڑھوائیں گے.اسی طرح عرش سے خود بھی تیری
تعریف کریں گے.اس کے مقابل پر دشمن کی گالیاں کیا حیثیت رکھتی ہیں.مقام محمود سے مراد مقام شفاعت بھی ہے کیونکہ جیسا کہ حدیثوں سے ثابت ہے.سب
اقوام کے لوگ سب نبیوں کے پاس سے مایوس ہو کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس
شفاعت کی غرض سے آئیں گے اور آپ شفاعت کریں گے.اس طرح گویا ان سب اقوام
کے مونہہ سے آپ کے لئے اظہار عقیدت کروادیا جائے گا جو اس دنیا میں آپ کو گالیاں دیتی
تھیں.اور یہ ایک نہایت اعلیٰ درجہ کا مقام محمود ہے.حمد مقام محمود سے مراد میرے نزدیک خروج مہدی بھی ہے.کیونکہ اس کے ظہور کا وقت
500
Page 509
وہی بیان ہوا ہے جب مسلمانوں کے اسلام سے روگردان ہوجانے کی اور کافروں کے کفر
میں ترقی کر جانے کی خبر دی گئی ہے.ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ کے اس پہلوان کا ظہور ان
گالیوں کی روکو تعریف سے بدلوا دے مقام محمود کا ہی ایک کرشمہ ہے.میں نے اسی خدمت
میں حصہ لینے کے لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات بیان کرنے کے لئے سال میں
ایک دن مقرر کیا ہوا ہے جس میں ہر مذہب و ملت کے لوگ اپنے ان تاثرات کو بیان کرتے
ہیں.جو آپ کے حالات پڑھنے سے ان کے دلوں میں پڑتے ہیں.رقيم الصلوة نماز پنجگانہ اور تہجد کے ذکر کے بعد جو مقام محمود کا ذکر کیا ہے اس میں
اس طرف اشارہ ہے کہ جس شخص کے دشمن زیادہ ہوں اور بدگولوگوں کی تعداد بڑھ جائے اس
کا علاج یہ نہیں کہ وہ ان سے الجھتا پھرے.بلکہ ایسے وقت میں انابت الی اللہ اور بارگاہ الہی
میں فریاد کرنا ہی ان فتنوں کو دور کرتا ہے بلکہ اگر انابت بہت بڑھ جائے تو مذمت تعریف
سے اور گالیاں دعاؤں سے بدل جاتی ہیں.چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ہی ہوا کہ
جولوگ آپ کو گالیاں دیتے تھے ایک دن عاشق صادق ہو گئے.مُدْخَلَ صِدْقٍ : لفظ مُدْخَلَ دَخَلَ سے باب افعال کا مصدر میمی.اسم مفعول او رظرف
زمان و مکان ہے.اس کے معنی داخل ہونا.داخل کیا ہوا.داخل ہونے کا وقت اور داخل
ہونے کی جگہ کے ہیں (اقرب) صدق کے معنی ہیں.نَقِيضُ الْكِذَبِ سچائی - الْفَضْلُ
فضیلت - الصَّلاحُ خوبی اور اچھائی.امجد.سنجیدگی.الشدَّةُ وَالصَّلابَةُ سختی اور مضبوطی.فَإِذَا اضَفْتَ إِلَيْهِ قُلْتَ رَجُلُ صِدْقٍ أَلَى نِعْمَ الرَّجُلُ اگر لفظ صدق مضاف الیہ واقع ہو
تو مضاف کی ہر رنگ کی خوبی پر دلالت کرتا ہے.چنانچہ رَجُلُ صِدْقٍ کے معنی ہوں گے.ہر لحاظ سے خوبیوں والا
شخص ( اقرب) وَيُعَبر عَنْ كُلَّ فِعْلٍ فَاضِلٍ ظَاهِرًا وَبَاطِنَّا بِصِدْقٍ
فَيُضَافُ إِلَيْهِ ذَلِكَ الْفِعْلُ الَّذِي يُوْصَفُ بِهِ کسی فعل کی ظاہری و باطنی خوبی کا اظہار کرنے
کے لئے اسے لفظ صدق کی طرف مضاف کیا جاتا ہے.پس مُدْخَلَ صِدْقٍ کے معنے
501
Page 510
ہوں گے ظاہر او باطنا اچھے طور پر داخل کرنا.صدق کے معنی بتائے جاچکے ہیں یعنی اندرونی و بیرونی دونوں حالتیں یکساں طور سے
اچھی ہوں.اس آیت میں دعا اور انابت کے جواب میں جو مقام محمو درسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کو ملنے والے تھے.ان میں سے پہلے مقام محمود کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اب تجھے
اسراء کی خبر کے ماتحت مکہ سے نکال کر ہم ایک اور جگہ کی طرف جو مقام محمود ہے لے جائیں
گے.اس لئے اس کے متعلق ابھی سے دعائیں شروع کر دے.اور کہہ کہ اے خدا مجھے اس شہر
میں ظاہری اور باطنی خوبیوں کے ساتھ داخل کر اور اس مقام سے بھی جس میں میں اس وقت ہوں
یعنی مکہ سے ظاہری اور باطنی خوبیوں کے ساتھ نکال یعنی کفار جو ارادہ کر رہے ہیں کہ مجھے ذلت
سے نکالیں.جس سے میرا رعب اور اثر جاتا رہے.اس میں وہ کامیاب نہ ہوں.چنانچہ یہ
دونوں دعائیں قبول ہوئیں.اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار اپنی مرضی کے مطابق نہ نکا
ل سکے بلکہ خدا تعالیٰ کے علم دینے سے آپ خود ہی مناسب موقعہ پر مکہ سے ہجرت کر گئے.اسی
طرح آپ کا دخول مقام محمود میں بھی نہایت اعلی ہوا.اللہ تعالیٰ نے وہاں آپ کی شمع رُخ کے
ہزاروں پروانے پیدا کر دئیے جو آپ کے منہ کی طرف ہر وقت دیکھتے رہتے تھے.اور جن کو
آپ سے وہ عشق تھا کہ اس عشق کی نظیر دنیا میں اور کہیں نہیں ملتی.ان معنوں پر ایک اعتراض ہو سکتا ہے اور وہ یہ کہ خروج مکہ پہلے ہوا ہے اور دخول مدینہ
بعد میں.پھر قرآن کریم نے دخول کو پہلے کیوں بیان فرمایا.اس کا جواب یہ ہے کہ خروج کی خبر
سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لازما تکلیف ہوئی تھی اور یہ خیال پیدا ہونا تھا کہ مکہ سے
نکل کر ہم کہاں جائیں گے.اس لئے اللہ تعالی نے اپنے رسول کی محبت کی وجہ سے اس امر
کا پہلے ذکر فرمایا کہ عنقریب تجھ کو ایک مبارک مقام ملنے والا ہے اور مکہ سے نکلنے کے ذکر کو
اس کے بعد رکھا تا کہ تسلی پہلے مل جائے اور غم کی خبر بعد میں ملے.دوسرے معنے اس آیت کے یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ دخول سے مراد آپ کا دوبارہ مکہ میں واپس
آنا ہے.اور خروج سے مراد آپ کی ہجرت ہے.اس صورت میں بھی ترتیب کے متعلق اعتراض
502
Page 511
پڑے گا کہ ہجرت پہلے تھی اور فتح مکہ بعد میں لیکن اس کا بھی وہی جواب ہے جو پہلے بیان
ہوا کہ مکہ سے نکلنے کے صدمہ کو اس خبر سے کم کر دیا کہ آپ پھر مکہ میں آنے والے ہیں.اور اس
کے بعد مکہ سے نکلنے کا ذکر کیا تا تسلی پہلے ہو جائے اور غم کی خبر بعد میں بتائی جائے.اس صورت
میں مقام محمود کے معنی یہ ہوں گے کہ فتح مکہ کے بعد دشمنوں کے سب اعتراضات دور ہوجائیں
گے اور عربوں پر آپ کی سچائی ظاہر ہو جائے گی.چنانچہ ایسا ہی ہوا.سُلْطَانًا نَصِيرًا مجھے اپنے
پاس سے ایسا غلبہ دے جو کہ نصیر ہو.یعنی وہ میرے کاموں میں میر احمد و معاون ہو مضر نہ ہو کیونکہ
بعض غلبے انسان کے لئے بجائے فائدہ پہنچانے کے نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں.یعنی مجھے
غلبہ تو ملے.مگر ایسا نہ ہوجس کا انجام میرے کاموں کی تباہی ہو.جَاءَ الْحَقُ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا
زَهَقَ زَهَقَ الْبَاطِلُ اِضْمَحَلَّ باطل کمزور ہو گیا.الشَّيءُ بَطَلَ وَهَلَكَ کوئی چیز
بے اثر ہو گئی ، مٹ گئی (اقرب)
اس میں یہ اشارہ کیا گیا ہے کہ مدنی زندگی کے شروع ہونے کے ساتھ ہی آنحضرت صلی
اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طاقت مضبوط ہوتی اور بڑھتی جائے گی اور دشمن کی کمزوری اور ضعف و ناتوانی کے
سامان پیدا ہوتے جائیں گے.یہاں تک کہ آخر باطل کمزور پڑتے پڑتے فنا ہو جائے گا اور مکہ کی
فتح کے وقت عرب سے بت پرستی کا ہمیشہ کے لئے خاتمہ کردیا جائے گا.قرآن کریم کا یہ بے نظیر
کمال ہے کہ وہ ہر موقعہ کے لئے ایسے الفاظ چنتا ہے جو ایک لمبے مضمون پر دلالت کرتے ہیں.اس آیت میں زَهَقَ کا لفظ رکھا ہے.اس کی جگہ هَلك اور بکل وغیرہ الفاظ بھی رکھے جاسکتے تھے مگر
ان سے باطل کی تباہی کی تدریج کا علم نہ ہوتا جو ھوق کے الفاظ سے بتائی گئی ہے.زھوق کے معنے
کمزور ہو جانے اور بلاک ہو جانے کے ہیں.اور اسی طرح مکہ والوں سے گزری.یہ نہیں کہ وہ یکدم
تباہ ہو گئے.بلکہ کمزور ہونے شروع ہوئے پستہ آہستہ وہ وقت آیا کہ بالکل فنا ہو گئے.پس زھوق
کے لفظ نے ہلاکت کی تفصیل بھی بتادی.جب مکہ فتح ہوا اور خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے بتوں کو توٹ کر پھینکا گیا.اس وقت رسول کریم
503
Page 512
صلی اللہ علیہ وسلم یہی آیت پڑھتے جاتے تھے.ایک ایک بت پر ضرب لگاتے اور فرماتے جاتے
تھے.قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا.یہ بھی قرآن کا معجزہ ہے کہ اس نے
کعبہ سے بتوں کے دور کئے جانے کے موقعہ کے لئے جو آیت رکھی ہے وہ شعر کی طرح موزوں
ہے.اس قسم کی خوشی کا موقعہ انسانی طبیعت کو شعر کی طرف راغب کرتا ہے.قرآن شعر نہیں مگر اس
کی آیات کے بعض ٹکڑے شعر کی سی موزونیت رکھتے ہیں.یہ آیت بھی اگر اس کے شروع سے قُل
کا لفظ اڑادیا جائے تو شعر کی طرح موزوں ہو جاتی ہے.جاءَ الْحَقُ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ایک مصرعہ اور
إنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا.دوسرا مصرعہ ہوتا ہے.قُل نے اس کو شعر کی تعریف سے نکال دیا.لیکن
جب اس کے پڑھنے کا موقعہ آیا تو چونکہ اس آیت کو قتل کے بغیر پڑھنا تھا اس وقت یہ آیت اپنے
شاندار معانی کے علاوہ ایک موزوں کلام کا بھی کام دیتی تھی.اور اس خوشی کے موقعہ کے عین
مناسب حال تھی.جَاءَ الْحَقُ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا.اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی چیز مختلف نظروں سے دیکھی جاتی ہے.اور جیسی کسی کی
فطرت ہوتی ہے.ایسا ہی وہ دوسری چیزوں کو سمجھتا ہے.کتناہی اعلیٰ اور پاک کلام کیوں نہ ہو.لیکن گندے دل والے انسان کو اس میں گند ہی نظر آتے ہیں.میں یہ دیکھ کر حیران رہ
جاتا ہوں کہ پنڈت دیانند صاحب کو قرآن مجید کے ابتدا سے لے کر آخر تک اعتراض ہی
اعتراض نظر آئے اور انہیں کوئی خوبی اس میں دکھائی نہ دی.یہی معنی اس آیت کے ہیں کہ ظالم
اس پر نکتہ چینیاں کر کے اور بھی اپنے گناہوں کو بڑھاتے ہیں.ان عام معنوں کے علاوہ میرے نزدیک اس آیت کے یہ معنی بھی ہیں کہ اس جگہ قرآن سے
مراد وہ خاص حصہ ہے جو پہلے اتر چکا ہے.یعنی مومنوں کی ترقی اور کامیابی کی پیشگوئیاں
اور دشمنوں کی بربادی اور تباہی کی خبریں.فرمایا کہ ان خبروں کے پورا ہونے کا وقت آ گیا
ہے.ان پیشگوئیوں کے نتیجہ میں مسلمانوں کے زخمی دلوں کو شفا حاصل ہوگی اور ان کے زخم
مندمل ہوں گے.ان کے ترقی کے سامان پیدا ہوں گے مگر یہی پیشگوئیاں کافروں کے حق میں
نقصان اور تباہی کے سامان ساتھ لائیں گی.نابجانبه نا کے معنے ہیں بعد دور ہوا.نابجانبہ کے معنی ہوں گے اس نے اپنے
504
Page 513
پہلو کوڈ ور کر لیا.( اقرب )
حمد اس میں بتایا کہ مومن اور کافر میں بڑا فرق ہے.مسلمانوں نے متواتر تیرہ سال تک
مشکلات اور مصائب برداشت کئے.ماریں کھائیں اور عذاب سہے مگر اُف تک نہ کی لیکن
ان کافروں پر جب عذاب شروع ہوگا اور مومنوں کی ترقی کے سامان ہوں گے تو یہ کفار اسی دن
ہتھیار ڈال دیں گے اور نا امید ہو جائیں گے.چونکہ کا فر کو خدا پر ایمان نہیں ہوتا اس لئے وہ
ذراسی تکلیف سے بھی گھبرا جاتا ہے.مگر مومن خدا کے لئے سب کچھ دلیری اور جرات سے
برداشت کرتا ہے.شاكلة.اس کا مادہ شکل ہے.اس کے معنی یہ ہیں الشكل صورت.شکل.النَّاحِيَةُ طرف النيَّةُ نيت الطَّرِيقَةُ طريق الْمَذْهَبُ.راستہ مذہب.الْحَاجَةُ.ضرورت.(اقرب)
فرماتا ہے منکرین سے کہہ دے کہ ہر شخص اپنے اپنے طریق پر اور اپنی اپنی شکل وصورت
اپنی اپنی قابلیت.اپنے اپنے دین اور اپنی اپنی نیت کے مطابق عمل کرتا ہے.مومن کی نیت چونکہ
خدا تعالیٰ کا حصول ہوتی ہے اس لئے وہ دنیا کے چلے جانے پر گھبرا تا نہیں.بلکہ سب ابتلاؤں
کا دلیری سے مقابلہ کرتا ہے.لیکن کافر چونکہ دنیا پرست ہوتا ہے اور اس کا سارا عمل دنیا کی خاطر
ہوتا ہے جب وہ دنیا کو جاتے دیکھتا ہے تو گھبرا کر ہتھیار ڈال دیتا ہے.فرمایا تمہارا رب خوب جانتا
ہے کہ کون ہدایت کی راہ پر عمل کر رہا ہے.یعنی خدا تعالیٰ بھی اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتا ہے.جیسی کہ اس شخص کی نیت ہوتی ہے.فرمایا ہم عمل کو بھی دیکھیں گے اور نیت کو بھی.اور پھر دونوں
کے مطابق معاملہ کریں گے.جو خدا تعالیٰ کی رضا کو مد نظر رکھیں گے اور اس کے دین کے لئے
قربانیاں کریں گے ان کی تائید ونصرت کی جائے گی.(ماخوذ از تفسیر کبیر)
حضرت خلیفہ مسیح الخامس
ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العز یز فرماتے ہیں:
ہمیشہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فقرہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہئے کہ جو
لوگ قرآن کو عزت دیں گے وہ آسمان پر عزت پائیں گے.ہم ہمیشہ قرآن کے ہر حکم اور ہر
505
Page 514
لفظ کو عزت دینے والے ہوں.اور عزت اس وقت ہوگی جب ہم اس پر عمل کر رہے ہوں گے.اور جب ہم اس طرح کر رہے ہوں گے تو قرآن کریم ہمیں ہر پریشانی سے نجات دلانے والا اور
ہمارے لئے رحمت کی چھتری ہوگا.جیسا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ
الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّلِمِينَ إِلَّا خَسَارًا (بنی اسرائیل:83).اور ہم قرآن میں سے وہ نازل کرتے ہیں جو شفا ہے اور مومنوں کے لئے رحمت ہے اور وہ
ظالموں کو گھاٹے کے سوا اور کسی چیز میں نہیں بڑھاتا.پس ہمیں چاہئے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے تمام اوامر ونواہی کو سامنے رکھیں اور
اس تعلیم کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں.اس کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں.تبھی ہم
روحانی اور جسمانی شفا پانے والے بھی ہوں گے اور قرآن کریم ہمارے لئے رحمت کا باعث بھی
ہوگا.اور عمل نہ کرنے والے تو ظالم ہیں اور ان کے لئے سوائے گھاٹے کے اور کچھ ہے ہی
نہیں، جیسا کہ قرآن شریف نے فرمایا.خطبہ جمعہ حضرت خلیفہ المسیح الخامس ایدہ اللہ فرموده 21 اکتوبر 2005ء - خطبات مسرور جلد سوم صفحہ 628-629)
506
Page 515
XXXXXXXXXXX
ورة الكهف آيات 01 تا 11
سور
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
1 - ( میں ) اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا
( اور ) بار بار رحم کرنے والا ہے (پڑھتا ہوں)
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَبَ 2.ہر تعریف کا اللہ ہی مستحق ہے جس نے ( یہ )
وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجًان
کتاب اپنے بندہ پر اتاری ہے اور اس میں کوئی
کجی نہیں رکھی.قَيِّمَا لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِنْ لَّدُنْهُ 3.( اور اس نے اسے) سچ سے معمور اور صحیح راہنمائی کرنے
وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ والی بنا کر اتارا ہے تا کہ وہ (لوگوں کو ) اس کی ( یعنی اللہ کی)
الصّلِحَتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنانُ
مَّاكِثِينَ فِيْهِ أَبَدًان
طرف سے ( آنے والے) ایک سخت عذاب سے آگاہ
کرے اور ایمان لانے والوں کو جو نیک ( اور ایمان کے
مناسب حال ) کام کرتے ہیں بشارت دے کہ ان کے لئے
( خدا کی طرف سے ) اچھا اجر ( مقدر) ہے.4.وہ اس ( اجر کے مقام ) میں ہمیشہ رہیں گے.وَيُنْذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًان 5.اور ( نیز اس نے اس لئے اسے اتارا ہے کہ )
تا وہ ان لوگوں کو (آنے والے عذاب سے)
آگاہ کرے جو یہ کہتے ہیں (کہ) اللہ نے (فلاں
شخص کو ) بیٹا بنالیا ہے.مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِاَبَا بِهِم 6.انہیں اس بارہ میں کچھ بھی تو علم ( حاصل ) نہیں
كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ اور نہ ان کے بڑوں کو اس بارہ میں کوئی علم
اِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا
تھا).یہ بہت بڑی (خطرناک) بات ہے جوان
کے مونہوں سے نکل رہی ہے ( بلکہ ) وہ محض جھوٹ
بول رہے ہیں.507
Page 516
فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى أَثَارِهِمْ 7- (کیا) اگر وہ اس عظیم الشان کلام پر ایمان نہ لائیں تو ٹو
إِن لَّمْ يُؤْمِنُوْا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا
ان کے غم میں شدت افسوس کی وجہ سے اپنی جان کو ہلاکت
میں ڈال دے گا.إنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِيْنَةً لَّهَا 8.جو کچھ ( رُوئے ) زمین پر (موجود) ہے اسے
یقیناً ہم نے اس کی زینت ( کا موجب ) بنایا ہے
لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا
تا کہ ہم ان کا امتحان لیں (کہ) ان میں سے سب
سے اچھا کام کرنے والا کون ہے.وَإِنَّا لَجُعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًات 9.اور جو کچھ اس ( زمین ) پر ( موجود ) ہے اسے ہم
یقیناً ( ایک دن ) مٹا کر ویران سطح بنا دیں گے.أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحُبَ الْكَهْفِ 10.کیا تو سمجھتا ہے کہ کہف اور رقیم والے (لوگ)
ہمارے نشانوں میں سے کوئی اچنبھا (نشان) تھے
وَالرَّقِيمِ كَانُوْا مِنْ أَيْتِنَا عَجَبًا
( جن کی نظیر پھر کبھی نہ پائی جاسکتی ہو )
إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا 11.جب وہ ( چند ) نوجوان وسیع غار میں پناہ گزیں
ہوئے اور ( دعا کرتے ہوئے) انہوں نے کہا
رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا
مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا
(کہ) اے ہمارے ربّ! ہمیں اپنے حضور سے
( خاص ) رحمت عطا کر اور ہمارے لئے ہمارے
( اس ) معاملہ میں رُشد و ہدایت کا سامان مہیا کر.508
Page 517
حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں:
حدیث میں آیا ہے کہ جب تم دنبال کو دیکھو توسورۃ کہف کی پہلی آیتیں پڑھو اور وہ یہ
ہیں الحمدُ للهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَبَ وَ لَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجًا.فَمَا لِيُنذِرَ بَأْسًا
شَدِيدًا مِن لَّدُنْهُ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللهُ وَلَدًا مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِأَبَاعِهِمْ
كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ اِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا
ان آیتوں سے ظاہر ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال سے کس گروہ کو مراد رکھا
ہے.اور عوج کے لفظ سے اس جگہ مخلوق کو شریک الباری ٹھہرانے سے مراد ہے جس طرح
عیسائیوں نے حضرت عیسی علیہ السلام کو ٹھہرایا ہے اور اسی لفظ سے فَيْجِ اعوج مشتق ہے اور
فَيْجِ آغوج سے وہ درمیانی زمانہ مراد ہے جس میں مسلمانوں نے عیسائیوں کی طرح حضرت مسیح
کو بعض صفات میں شریک الباری ٹھہرا دیا.اس جگہ ہر ایک انسان سمجھ سکتا ہے کہ اگر دنبال کا
بھی کوئی علیحدہ وجود ہوتا تو سورہ فاتحہ میں اس کے فتنہ کا بھی ذکر ضرور ہوتا اور اس کے فتنہ سے
بچنے کے لئے بھی کوئی علیحدہ دعا ہوتی.مگر ظاہر ہے کہ اس جگہ یعنی سورہ فاتحہ میں صرف مسیح موعود
کوایذا دینے سے بچنے کے لئے اور نصاریٰ کے فتنے سے محفوظ رہنے کے لئے دعا کی گئی ہے
حالانکہ بموجب خیالات حال کے مسلمانوں کا دنجال ایک اور شخص ہے اور اس کا فتنہ تمام فتنوں
سے بڑھ کر ہے.تو گویا نعوذ باللہ خدا بھول گیا کہ ایک بڑے فتنہ کا ذکر بھی نہ کیا اور صرف دو
فتنوں کا ذکر کیا ایک اندرونی یعنی مسیح موعود کو یہودیوں کی طرح ایذا دینا دوسرے عیسائی مذہب
اختیار کرنا.یاد رکھو اور خوب یاد رکھو کہ سورۃ فاتحہ میں صرف دوفتنوں سے بچنے کے لئے دعا
سکھلائی گئی ہے.(1) اوّل یہ فتنہ کہ اسلام کے مسیح موعود کو کافر قرار دینا، اس کی توہین کرنا،
اس کی ذاتیات میں نقص نکالنے کی کوشش کرنا، اس کے قتل کا فتویٰ دینا جیسا کہ آیت
غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْہم میں انہیں باتوں کی طرف اشارہ ہے.509
Page 518
(2) دوسرے نصاریٰ کے فتنے سے بچنے کے لئے دعا سکھلائی گئی اور سورۃ کو اسی کے ذکر
پر ختم کر کے اشارہ کیا گیا ہے کہ فتنہ نصاری ایک سیل عظیم کی طرح ہوگا.اس سے بڑھ کر کوئی
فتہ نہیں.(تحفہ گولڑویہ، روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 210، 212)
کیا تم خیال کرتے ہو کہ ہمارے عجیب کام فقط اصحاب کہف تک ہی ختم ہیں.نہیں.بلکہ خدا تو ہمیشہ صاحب عجائب ہے اور اس کے عجائبات کبھی منقطع نہیں ہوتے.( براہین احمدیہ، روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 562 حاشیہ در حاشیہ نمبر 4)
میں دیکھتا ہوں براہین میں میرا نام اصحاب الکہف بھی رکھا ہے.اس میں یہ سر ہے کہ
جیسے وہ مخفی تھے اسی طرح پر تیرہ سو برس سے یہ راز مخفی رہا اور کسی پر نہ کھلا.اور ساتھ اس کے جو
رقیم کا لفظ ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ باوجود مخفی ہونے کے اس کے ساتھ ایک کتبہ بھی
ہے.اور وہ کتبہ یہی ہے کہ تمام نبی اس کے متعلق پیشگوئی کرتے چلے آئے ہیں.احکم جلد 9 نمبر 28 مورخہ 10 / اگست 1905 ، صفحه (2)
لا...مجھے بھی الہام ہوا تھا آم حَسِبْتَ اَنَّ اَصْحَبَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ أَيْتِنَا
حضرت
خلیفہ المسیح الاول رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:
احکم جلد 10 نمبر 6 مورخہ 7 فروری 1906 صفحہ 3)
حدیث شریف میں آیا ہے کہ فتنہ دجال سے بچنے کے واسطے ہر جمعہ کو سورۃ کہف کی
پہلی دس آیتیں اور پچھلی دس آیتیں پڑھو.ان آیات کے مطالعہ سے واضح ہو سکتا ہے کہ دجال
کون ہے اور اس کے کیا صفات ہیں اور اس سے بچنے کی کیا راہ ہے.ا ما : 1 - مُسْتَقِيما - بالکل سیدھے راہ پر اور سیدھی راہ بتانے والی 2.مُصدّق اور
صداقتوں کی اور اپنی صداقتوں کی 3.حافظ اس پر عمل کرنے والوں کے لئے.شدید کا لفظ ظاہر کرتا ہے کہ خدا تعالیٰ ایسے لوگوں کے ساتھ سخت مخالفت کے واسطے تیار ہے.510
Page 519
وَيُنْذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا
یہ آیت بتلاتی ہے کہ قوم دجال کون ہے.مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِأَبَاءِ هِمْ
(ضمیمه اخبار بدر قادیان 10 مارچ 1910ء صفحہ 155)
یہ قوم بڑی سائنسدان بن گئی.ہر بات پر دلیل پیش کرتی ہے.مگر اپنے مذہب کے
متعلق صاف اقرار کرتے ہیں کہ مسیح کے ابن خدا ہونے اور تثلیث، کفارہ وغیرہ کے واسطے
دلیل کوئی نہیں.قرآن شریف نے پہلے سے پیشگوئی کی ہے کہ یہ ایسا کہیں گے.أَفْوَاهِهِمْ : منہ سے نکلتی ہے.دل سے نہیں نکلتی.دل جانتے ہیں کہ یہ بے دلیل
بات ہے صحیح نہیں.نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کشف میں اس قوم کا جاہ و حشم دکھایا گیا جس سے آپ کو غم
ہوا کہ اتنی بڑی بظاہر معر: زقوم اسلام کی نعمت سے بے نصیب رہے گی.تو ان کی وجاہت کتنوں کو
اسلام سے مرتد کر دے گی.اس پر خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سب اشیاء عارضی اور زمینی ہیں.( ضمیمه اخبار بدر قادیان 10 / مارچ 1910، صفحه 155)
حضرت خلیفۃالمسیح الثانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں :
قيما..الخ (1) وہ بطور داروغہ کے ہے پچھلی کتابوں پر تاکہ ان کی غلطیوں کو
ڈور کرے(2) نیز داروغہ ہے آئندہ زمانے کے لوگوں پر کیونکہ انہیں ان اعمال کی اطلاع
دیتی ہے جو انہیں کرنے چاہئیں.لغت میں قیمُ الْآمر کے معنے متولی کے لکھے ہیں.یعنی قیم الآمر وہ ہے جس کے سپرد
نگرانی اور تربیت ہو.ان معنوں کے رو سے آیت کے یہ معنے ہوں گے کہ یہ کتاب آنے والے
لوگوں کے لئے مربی ہے اور پہلوں کے لئے نگران.ليُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا - عربی زبان میں بوش کے معنے تنگی اور فقر کے ہوتے ہیں
511
Page 520
اور باس کے معنے بہادری اور طاقت کے یا خوف، عذاب اور جنگ کے ہوتے ہیں.اس جگہ
خوف اور عذاب کے معنے ہیں.ويُبَشِّرَ المُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّلِحَتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا.م اس آیت میں مومنوں سے اجر حسن کا وعدہ کیا گیا ہے.اجر حسن سے مراد صرف یہ نہیں کہ
انہیں انعامات ملیں گے کیونکہ یہ معنے خالی اجر سے بھی نکل آتے ہیں.چنانچہ کئی جگہ قرآن کریم میں
صرف اجر کا لفظ مومنوں کے لئے استعمال ہوا ہے.مثلاً اس سورۃ میں آگے چل کر فرماتا ہے انا
لا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا.ہم نیکوں کے اجر کو ضائع نہیں کریں گے.یہاں موقعہ کے لحاظ
سے اجر کے معنے اچھے اجر کے ہیں.اسی طرح اس آیت میں بھی خالی اجر کا لفظ استعمال
کیا جاتا تو اس کے معنی موقعہ کے مطابق اچھے اجر کے ہی ہوتے.پس آجرًا حَسَنًا کہہ کر اس
طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ اجر نیک نتیجہ پیدا کرنے والا ہوگا.اس کے ملنے سے مومن بگڑیں گے
نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اچھے طور پر استعمال کر کے مزید ثواب اپنے لئے جمع کریں گے.مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا -
وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے.یعنی ان کا وہ اجر کبھی ختم نہ ہو گا.اس سے یہ مراد نہیں کہ کسی
صورت میں بھی ختم نہ ہوگا.بلکہ مطلب یہ ہے کہ جب تک وہ مومن رہیں گے اجر ملتا رہے گا.یہ
معنے اس صورت میں ہیں کہ اس آیت کو ان انعامات کے متعلق سمجھا جائے جومومنوں کو دنیا
میں ملنے والے ہیں.لیکن اگر اخروی انعامات لئے جائیں تو پھر یہی معنی ہوں گے کہ وہ ہمیشہ
اس اجر سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے.کبھی بھی ان کا اجر ختم نہ ہوگا.اس آیت میں اشارہ کیا ہے
کہ اگر دائمی فضل چاہتے ہو تو ایمان کو کبھی ہاتھ سے نہ دینا.عملا ولد کے اصل معنے اولاد کے ہیں.خواہ نر ہو یا مادہ لیکن چونکہ اس جگہ بیٹا مراد
ہے.ترجمہ میں بیٹے کا لفظ استعمال کیا گیا.الْكَلِمَةُ : کے معنے ہیں لفظ یا جو کچھ بولیں خواہ مفرد ہو یا مرکب.512
Page 521
ی کسی چیز کے متعلق باوجود علم کے خلاف واقعہ خبر دینا کذب کہلاتا ہے اور یہ لفظ صدق
کے مخالف معنوں کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے.وَسَوَاءُ فِيهِ الْعَبَدُ وَالْخَطَاء اور اس صورت میں
جان بوجھ کر خلاف حقیقت بات کہنا یا غلطی سے کہنا دونوں کذب میں شامل ہوتے ہیں.(اقرب)
پہلے کتاب کا کام انذار بتایا.پھر مومنوں کو بشارت دینا اس کا کام بتایا.اس کے بعد
پھر انذار کا ذکر کیا.اور یہ انذار خاص اس قوم کے متعلق
بتایا جو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بناتے ہیں.اس پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں انذار کا ذکر اکٹھا نہ رکھا اور بشارت کا ذکر بعد میں نہ رکھا.اس کا جواب یہ ہے کہ اس ترتیب سے قرآن کریم نے ان زمانوں کا بھی اظہار کر دیا ہے جن
میں قرآن کریم کا انذار تبشیر اور پھر دوسرا اندار ظاہر ہوگا.پہلے اندار سے ملنے والوں اور دوسری
تمام ان اقوام کا اندار مراد ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام کی مخالف
تھیں.چنانچہ قرآن کریم کے اس اندار کے نتیجے میں وہ اقوام تباہ کی گئیں.اس کے بعد
مومنوں کی بشارت کا ذکر کیا.چنانچہ مخالفین اسلام کی تباہی کے بعد مسلمانوں کو انعام ملے اور
مَاكِثِينَ فِيهِ ابدا کے حکم کے ماتحت مسلمانوں نے صدیوں تک دنیا میں حکومت کی.اس
کے بعد صرف مسیحی قوم کے اندار کا ذکر کیا جس سے اس طرف اشارہ ہے کہ اسلامی ترقی کے
بعد پھر مسیحیت زور پکڑے گی اور دنیا پر اس طرح چھا جائے گی کہ گویا وہی ایک قوم اسلام کے
مخالف رہ جائے گی.اس وقت قرآن کا انذار خصوصیت سے مسیحی اقوام کے لئے ہوگا.اگر اس
طرح اندار کو دو ٹکڑوں میں تقسیم نہ کیا جاتا اور مسلمانوں کے انعامات کو درمیان میں بیان نہ
کیا جاتا تو یہ لطیف معنے جو عذاب کے اوقات اور آئندہ زمانے کے سیاسی تغیرات کو بھی
ظاہر کر رہے ہیں ، پیدا نہ ہو سکتے تھے.كَبُرَتْ كَلِمَةٌ.اس میں بتایا ہے کہ نہایت گستاخی کا عقیدہ ہونے کے علاوہ اس
عقیدے کو تو انسانی عقل بھی رد کرتی ہے.یہ کس طرح ہوسکتا ہے کہ ایک انسان پھانسی پر
چڑھایا جائے اور پھر وہ خدا کا بیٹا کہلائے.513
Page 522
مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِأَبَاعِهِمْ
اندار کی خبر دیتے ہوئے مسیحیت پر ایک کاری ضرب بھی لگادی.فرماتا ہے کہ
بیٹا تو خدا کا بناتے ہیں لیکن بیٹا ہونے کی کوئی دلیل ان کے پاس موجود نہیں.نہ ان کے
باپ دادوں کے پاس تھی.یعنی باپ داووں نے یہ دیکھتے ہوئے کہ مسیح کے حواری اور ان کے
شاگردموجد تھے شرک بعد میں پیدا ہوا ہے اسے خدا کا بیٹا بنادیا اور ان کے پاس اعلیٰ توحید کی
تعلیم اسلام نے پیش کردی ہے اور مشرکانہ خیالات کا پوری طرح قلع قمع کردیا ہے.مگر نہ
پہلوں نے اپنی آنکھوں دیکھی باتوں سے فائدہ اٹھایا اور نہ بعد میں آنے والوں نے اسلام کے
دلائل سے نفع حاصل کیا.دونوں گروہوں نے بغیر دلیل اور بغیر ثبوت کے اپنے رب کو چھوڑ کر
ایک انسان کو خدا بنالیا.إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا
الَّا كَذِباً کہہ کر بتایا کہ خود مسیح بھی اس قسم کی اہنیت سے منکر ہے.چنانچہ موجودہ اناجیل
سے بھی مسیح کے خدا کا بیٹا ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا.بیشک مسیح علیہ السلام کی نسبت بیٹے کے
الفاظ آتے ہیں لیکن یہ الفاظ دوسرے انسانوں کے لئے بھی آتے ہیں.چنانچہ خروج باب 2 آیت
22 میں لکھا ہے کہ خداوند نے یوں فرمایا ہے کہ اسرائیل میرا بیٹا بلکہ پلوٹھا بیٹا ہے“.فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ کے معنی ہیں...کہ شائد تو اپنے نفس کو ان کے اسلام میں داخل
ہونے کی شدید خواہش سے ہلاکت میں ڈال دے گا
إنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا
فرماتا ہے ہم نے دنیا میں ہزاروں چیزیں پیدا کی ہیں اور غرض یہ ہے کہ انسان کے
لئے ایک شغل پیدا کریں تا وہ ان اشیاء کو دریافت کرے پھر ان سے کام لے.اور زینة کہہ کر
اس طرف اشارہ کیا ہے کہ دنیا کی ہر چیز کوئی نہ کوئی فائدہ رکھتی ہے.کوئی بھی ایسی چیز نہیں
جس میں کوئی فائدہ نہ ہو.اسی ایک لفظ سے کس طرح اس نکتہ کو واضح کر دیا گیا ہے کہ دنیا کی
514
Page 523
کوئی چیز لغو نہیں.اگر بعضها زینہ ہوتا تو یہ خیال کیا جاسکتا تھا کہ بعض اشیاء مفید ہیں
اور بعض غیر مفید مگر اللہ تعالیٰ سب اشیاء کو جو دنیا پر ہیں دنیا کے لئے زینت کا موجب
قرار دیتا ہے.پس معلوم ہوا کہ اسلام کے نزدیک دنیا کی ہر شے میں فوائد ہیں اور وہ ایک
حسن یعنی خوبی اپنے اندر رکھتی ہے اور کوئی بھی چیز نہیں جو دنیا کا حسن بڑھانے والی نہ
ہو.افسوس کہ اس حکم سے مسلمانوں نے فائدہ اٹھانا چھوڑ دیا اور تحقیق اور ایجاد کے کام کو
نظر انداز کر دیا.اور یورپ نے باوجود قرآن کریم کو نہ ماننے کے اس حکم پر عمل کیا اور علم میں
اس قدر ترقی کی کہ ساری دنیا پر غالب آگئے.لِتَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا
میں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ دنیا کی اشیاء اس لئے پیدا کی گئی ہیں تا کہ لوگ ان
کے متعلق تحقیق کریں، دنیا کی حالت کو سدھاریں.اس حصے کے متعلق مسیحیوں سے کوتاہی
ہوئی ہے.انہوں نے دنیا کے راز تو دریافت کئے مگر اچھے عمل کا نمونہ نہ دکھایا.یعنی اس تحقیق
اور تدقیق کے نتیجہ میں انہوں نے دنیا میں ظلم اور فساد کی بنیا درکھ دی اور غالباً اس طرف اس آیت
میں اشارہ کیا گیا ہے.فرمایا وہ دنیا کا سامان تو ایک عارضی چیز اور عارضی سامان ہے.حقیقی نہیں.صرف قومی مقابلہ
کا ایک ذریعہ خدا تعالیٰ نے بنایا ہے تا بنی نوع انسان کی خدمت کر کے ثواب حاصل کریں
لیکن مسیحی لوگ اس غرض کو پوری نہ کریں گے.خدا کے پیدا کئے ہوئے سامانوں کی
جستجو تو کریں گے لیکن ان کو حسن عمل کا ذریعہ نہ بنائیں گے اور لڑائی جھگڑے کا ذریعہ بنالیں گے.پس چونکہ ہمارا مقصد تو ان اشیاء کے پیدا کرنے سے دنیا کو زینت دینا ہے چونکہ وہ مقصد ان کی
تحقیقاتوں اور ایجادوں سے پورا نہ ہوگا.ہم ان کے کام کو مٹادیں گے.غرض اس جگہ سب دنیا کی
تباہی مراد نہیں بلکہ ان کاموں کی تباہی مراد ہے جو اللہ کا بیٹا بنانے والی قوم کرے گی.اس آیت کے الفاظ میں نہایت لطیف طور پر ایک تمثیل کی طرف جو اس سورۃ میں آگے چل
515
Page 524
کر بیان ہوئی ہے اشارہ فرمایا گیا ہے اور وہ اشارہ صَعِيدًا جُرُزًا کے الفاظ میں ہے.صعِيدًا کے معنے اس زمین کے ہوتے ہیں جس میں سے درخت وغیرہ کٹ جائیں.چنانچہ
عرب کا محاورہ ہے صَارَتِ الْحَدِيقَةُ صَعِيدًا (تاج) باغ اُجڑ گیا اس کے درخت فنا ہو گئے.اور جرز کے معنی بھی اس زمین کے ہوتے ہیں جس کی سبزی تباہ ہوگئی ہو.آگے چل کر جہاں
دو باغوں کی تمثیل دی گئی ہے (کہف رکوع (5) وہاں بھی متکبر باغوں والے کو اس کا ناصح
بھائی کہتا ہے کہ تو تکبر نہ کر.ایسا نہ ہو کہ آسمانی عذاب نازل ہو کر تیرے باغوں کو صَعِید از لقا
بنادے.صعِيدًا کا لفظ تو وہی ہے جو یہاں استعمال ہوا ہے.جُرُزًا کی جگہ وہاں زلفا کا لفظ رکھا
گیا ہے.اور اس کے معنے بھی یہی ہیں کہ جہاں کوئی کھیتی نہ ہو.عرب کہتے ہیں کہ ارض زلفی
ایسی زمین جس پر کوئی کھیتی نہ ہو.پس اس آیت سے اس طرف اشارہ ہے کہ آگے جو تمثیل بیان
کی گئی ہے مسیحی قوم بھی اس میں شامل ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے لگائے ہوئے باغوں کو تباہ
کردے گا.الْكَهْفُ كَالْبَيْتِ الْمَنْقُورِ فِي الْجَبَلِ گھر کی شکل پر پہاڑ میں کھود کر بنایا
ہوا مکان.اس کی جمع کھوف آتی ہے.غار اور گھف میں یہ فرق ہے کہ گھف وسیع ہوتی
،
ہے اور غار تنگ - اَلْكَهْفُ أَيْضًا الْوَزْرُ حفاظت کی جگہ الْمَلْجَأُ.پناہ کی جگہ.الرَّقِيمُ : الْكِتَابُ الْمَرْقُوْمُ - لکھی ہوئی چیز.اصحاب الرقیم کے معنے ہوں گے.نقش یا تصویر میں بنانے والے لوگ.مفسرین نے لکھا
ہے کہ پتھر یا لوہے پر کھو دنے والے لوگ.تو اس لحاظ سے یہ معنے ہوں گے پتھروں پر
یا کاغذوں پر لکھنے والے یا نقش و نگار کرنے والے یا تصویر میں بنانے والے یا کھودنے والے.رقيم بمعنے مرقوم بھی ہو سکتا ہے.اس لحاظ سے اصحاب الرقیم کے معنے ہوں گے جن کے
پاس لکھی ہوئی چیزیں ہوں.یعنی کتابیں یا سامان جن پر نام لکھا ہوا ہو یا کتبوں والے وغیرہ وغیرہ.عجبا
1.جب کوئی ایسا امر پیش آئے کہ اس کے ماننے میں طبیعت کو انقباض اور انکار ہو تو اس
516
Page 525
انکار کی حالت کو عجب کہتے ہیں.2.پیش آمدہ امر کے پسند کرنے کو بھی عجب کہتے ہیں.3.اس حالت رعب کو بھی عجب کہتے ہیں جو انسان پر کسی چیز کو بہت ہی بڑا سمجھنے کے وقت
طاری ہوتی ہے.(اقرب)
(ماخوذ از تفسیر کبیر )
حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز فرماتے ہیں:
اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی تو اس نے اس عقل کو استعمال کر کے اپنی آسانیوں
کے سامان پیدا کئے.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ
أَيُّهُمْ أَحْسَن عملًا.(الکھف (8) یعنی زمین پر جو کچھ ہے اُسے یقینا ہم نے زینت بنایا ہے تا
کہ ہم انہیں آزمائیں کہ کون بہترین عمل کرتا ہے.پس یہاں زمین کی ہر چیز کو زینت قرار دے کر اُس کی اہمیت بھی بیان فرما دی.ہر نئی ایجاد
جو ہم کرتے ہیں اُس کو بھی زینت بتا دیا، اُس کی اہمیت بیان فرمائی لیکن فرمایا کہ ہر چیز کی
اہمیت اپنی جگہ ہے لیکن اس کا فائدہ تبھی ہے جب احسن عمل کے ساتھ یہ وابستہ ہو.پس
ہمیں نصیحت ہے کہ ان ایجادات سے فائدہ اٹھاؤ لیکن احسن عمل مڈ نظر رہے.یہ ایجادات ہیں،
ان کی خوبصورتی تبھی ہے جب اس سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق کام کیا جائے یا لیا جائے ، نہ
که فتنه و فساد پیدا ہو.اگر احسن عمل نہیں تو یہ چیزیں ابتلا بن جاتی ہیں.جیسا کہ پہلے میں نے
مثالیں دیں.یہ ٹیلی ویژن ہی ہے جو فائدہ بھی دے رہا ہے اور ابتلا بھی بن رہا ہے.بہت
سے گھر انٹرنیٹ اور چیٹنگ کی وجہ سے برباد ہورہے ہیں.بچے خراب ہورہے ہیں اس لئے کہ
آزادی کے نام پر اللہ تعالیٰ کی مہیا کی گئی چیزوں کا ناجائز فائدہ اٹھایا جا رہا ہے.حقیقی عبد کے
66
لئے حکم ہے کہ ہمیشہ احسن قول اور احسن عمل کو سامنے رکھو اور کام کا مقصد اللہ تعالی کی رضا ہو.“
خطبہ جمعہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید واللہ تعالیٰ فرمودہ 18 اکتوبر 2013ء ،خطبات مسرور جلد 11 صفحہ 577)
517
Page 527
XXXXXXXXXXXXX
سورة الكهف آيات 103 تا 111
أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا 103 - ( تو ) کیا ( یہ سب کچھ دیکھ کر ) پھر (بھی)
وہ لوگ جنہوں نے کفر ( کا طریق) اختیار کیا ہے
عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا
( یہ ) سمجھتے ہیں کہ وہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو
مددگار بناسکیں گے.ہم نے کافروں کے انعام ( یعنی
جَهَنَّمَ لِلْكُفِرِينَ نُزُلًا
بدلہ ) کے طور پر جہنم کو تیار کر رکھا ہے.قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِيْنَ أَعْمَالًا 104.تو (انہیں) کہہ (کہ) کیا ہم تمہیں ان لوگوں
سے آگاہ کریں جو اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ گھاٹا
پانے والے ہیں.الَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَوةِ الدُّنْيَا 105 - ( یہ وہ لوگ ہیں) جن کی (تمام تر)
کوشش اس ورلی زندگی میں ہی غائب ہو گئی ہے
وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ
صنعان
اور (اس کے ساتھ ) وہ (یہ بھی) سمجھتے ہیں کہ وہ
اچھا کام کر رہے ہیں.أُولَئِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا بِايْتِ رَبِّهِمْ 106.یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے
وَلِقَابِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيْمُ نشانوں کا اور اس سے ملنے کا انکار کر دیا ہے اور اس
لئے ان کے ( تمام ) اعمال گر کر ( اسی دنیا میں) رہ
لَهُمْ يَوْمَ الْقِيِّمَةِ وَزْنًا
گئے ہیں چنانچہ قیامت کے دن ہم انہیں کچھ بھی
وقعت نہیں دیں گے.ذلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا 107 - یہ ان کا بدلہ (یعنی) جہنم اس وجہ سے ہوگا
کہ انہوں نے کفر ( کا طریق) اختیار کیا.اور
میرے نشانوں اور میرے رسولوں کو (اپنی) ہنسی کا
وَاتَّخَذُوا أَيْتِي وَرُسُلِى هُزُوًات
نشانہ بنالیا.اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ كَانَتْ 108.جولوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک
519
Page 528
لَهُمْ جَنَّتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا
اور مناسب حال ) عمل کیے ہیں ان کا ٹھکانا یقیناً
فردوس نامی بہشت ہوں گے.خُلِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا 109.وہ ان میں رہتے چلے جائیں گے ( اور ) ان
سے الگ ہونا نہیں چاہیں گے.قُل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَتِ رَبِّي 110.تو انہیں کہہ ( کہ ) اگر ( ہر ایک ) سمندر
میرے رب کی باتوں (کے لکھنے) کے لئے
لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَتُ رَبِّي روشنائی بن جاتا تو میرے رب کی باتوں کے ختم
وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا
ہونے سے پہلے ( ہر ایک) سمندر ( کا پانی ) ختم
ہو جا تا گو (اسے) زیادہ کرنے کے لئے ہم اتنا
(ہی) اور ( پانی سمندر میں لاڈالتے.قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَى 111.تو (انہیں) کہہ (کہ) میں صرف تمہاری
انَّمَا الهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ ۚ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا طرح کا ایک بشر ہوں.( فرق صرف یہ ہے کہ)
میری طرف ( یہ ) وحی ( نازل ) کی جاتی ہے کہ تمہارا
يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّةٍ أَحَدًا ®
لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا معبود ایک ہی ( حقیقی ) معبود ہے.پس جو شخص اپنے
رب سے ملنے کی امید رکھتا ہو اسے چاہیے کہ نیک ( اور
مناسب حال ) کام کرے اور اپنے رب کی عبادت میں
کسی کو بھی شریک نہ کرے.520
Page 529
أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَيْتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا
نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيمَةِ وَزُنًا.حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں:
(الكهف (106)
فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِیمَةِ وَزُنًا میں گناہ کا ذکر نہیں ہے.اس کا باعث صرف یہ
ہے کہ ان لوگوں نے دنیا کی خواہشوں کو مقدم رکھا ہوا تھا.ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ
وہ لوگ دنیا کا حظ پاچکے.وہاں بھی گناہ کاذ کر نہیں بلکہ دنیا کی لذات جن کو خدا تعالیٰ نے جائز کیا
ہے ان میں منہمک ہو جانے کا ذکر ہے.اس قسم کے لوگوں
کا مرتبہ عند اللہ کچھ نہ ہوگا اور نہ ان کو
کوئی عزت کا مقام دیا جائے گا.شیریں زندگی اصل میں ایک شیطان ہے جو کہ انسان کو دھو کہ
دیتی ہے.مومن تو خود مصیبت خریدتا ہے ورنہ اگر وہ مداہنہ برتے تو ہر طرح آرام سے رہ سکتا
ہے.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس طرح کرتے تو اس قدر جنگیں کیوں ہوتیں لیکن آپ نے
دین کو مقدم رکھا اس لئے سب دشمن ہو گئے.( البدر جلد 3 نمبر 29 مورخہ یکم اگست 1904ء صفحہ 3)
مؤمن آدمی کا سب ہم و غم خدا کے واسطے ہوتا ہے دنیا کے لئے نہیں ہوتا اور وہ دنیاوی
کاموں کو کچھ خوشی سے نہیں کرتا بلکہ اداس سا رہتا ہے اور یہی نجات حیات کا طریق ہے.اور
وہ جو دنیا کے پھندوں میں پھنسے ہوئے ہیں اور ان کے ہم وغم سب دنیا کے ہی لئے ہوتے
ہیں.ان کی نسبت تو خدا تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيمَةِ وَزْنا ہم قیامت کو ان کا
ذرہ بھر بھی قدر نہیں کریں گے.الحکم جلد 11 نمبر 34 مورخہ 24 ستمبر 1907 ، صفحہ 9)
521
Page 530
قُل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ
كَلِمَتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا مِثْلِهِ مَدَدًا
یعنی اگر خدا کی کلام کے لکھنے کے لئے سمندر کو سیاہی بنایا جائے تو لکھتے لکھتے سمندر ختم
ہوجائے اور کلام میں کچھ کمی نہ ہو.گو ویسے ہی اور سمندر بطور مدد کے کام میں لائے جائیں.رہی یہ بات کہ ہم لوگ ختم ہو نا وحی کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کن معنوں سے مانتے ہیں.سو
اس میں اصل حقیقت یہ ہے کہ گو کلام الہی اپنی ذات میں غیر محدود ہے.لیکن چونکہ وہ مفاسد کہ
جن کی اصلاح کے لئے کلام الہی نازل ہوتی رہی یا وہ ضرورتیں کہ جن کو الہام ربانی پورا کرتا رہا
ہے.وہ قدر محدود سے زیادہ نہیں ہیں.اس لئے کلام الہی بھی اسی قدر نازل ہوئی ہے کہ جس
قدر بنی آدم کو اس کی ضرورت تھی.اور قرآن شریف ایسے زمانہ میں آیا تھا کہ جس میں ہر ایک
طرح کی ضرورتیں کہ جن کا پیش آنا ممکن ہے پیش آگئی تھیں.یعنی تمام امور اخلاقی اور اعتقادی
اور قولی اور فعلی بگڑ گئے تھے اور ہر ایک قسم کا افراط تفریط اور ہر ایک نوع کا فسادا اپنے انتہا کو پہنچ
گیا تھا.اس لئے قرآن شریف کی تعلیم بھی انتہائی درجہ پر نازل ہوئی.پس انہیں معنوں سے
شریعت فرقانی مختم اور مکمل ٹھہری اور پہلی شریعتیں ناقص رہیں کیونکہ پہلے زمانوں میں وہ مفاسد
کہ جن کی اصلاح کے لئے الہامی کتابیں آئیں وہ بھی انتہائی درجہ پر نہیں پہنچے تھے اور
قرآن شریف کے وقت میں وہ سب اپنی انتہا کو پہنچ گئے تھے.بس اب قرآن شریف اور
دوسری الہامی کتابوں میں فرق یہ ہے کہ پہلی کتابیں اگر ہر ایک طرح کے خلل سے محفوظ بھی
رہتیں.پھر بھی بوجہ ناقص ہونے تعلیم کے ضرور تھا کہ کسی وقت کامل تعلیم یعنی فرقان مجید ظہور
پذیر ہوتا.مگر قرآن شریف کے لئے اب یہ ضرورت در پیش نہیں کہ اس کے بعد کوئی اور کتاب
بھی آوے.کیونکہ کمال کے بعد اور کوئی درجہ باقی نہیں.ہاں اگر یہ فرض کیا جائے کہ کسی
وقت اصول حقہ قرآن شریف کے وید اور انجیل کی طرح مشرکانہ اصول بنائے جائیں گے اور
تعلیم توحید میں تبدیل اور تحریف عمل میں آوے گی.یا اگر ساتھ اس کے یہ بھی فرض کیا جائے
522
Page 531
جو کسی زمانہ میں وہ کروڑ با مسلمان جو توحید پر قائم ہیں وہ بھی پھر طریق شرک اور مخلوق پرستی کا
اختیار کرلیں گے تو بے شک ایسی صورتوں میں دوسری شریعت اور دوسرے رسول کا آنا ضروری
ہوگا.مگر دونوں قسم کے فرض محال ہیں.قرآن شریف کی تعلیم کا محرف مبذل ہونا اس لئے محال
ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے اِنا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِكرَ وَإِنَّالَهُ لَحفِظُونَ (الحجر: 10)
برائین احمد یہ چہار حصص ، روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 101 102 حاشیہ نمبر 9)
قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَى انَّمَا الهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ
يَرْجُو القَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّةِ أَحَدًا
فَمَن كَانَ يَرْجُو القَاءَ رَبِّهِ الخ جو شخص خدا کی ملاقات کا طالب ہے اسے لازم ہے کہ ایسا
عمل اختیار کرے جس میں کسی نوع کا فساد نہ ہو اور کسی چیز کو خدا کی بندگی میں شریک نہ کرے.( براہین احمدیہ چہار حصص، روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 239 حاشیه در حاشیہ نمبر 3)
جو شخص خدا تعالیٰ کا دیدار چاہتا ہے چاہئے کہ وہ ایسے کام کرے جن میں فساد نہ ہو.یعنی
ایک ذرہ متابعت نفس اور ہوا کی نہ ہو.اور چاہئے کہ خدا کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ
کرے بنفس کو ، نہ ہوا کو اور نہ دوسرے باطل معبودوں کو.ست بچن، روحانی خزائن جلد 10 صفحه 230)
مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَ لَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبَّةٍ أَحَدًا.یعنی
جوشخص چاہتا ہے کہ اسی دنیا میں اس خدا کا دیدار نصیب ہو جائے جو حقیقی خدا اور پیدا کنندہ ہے
پس چاہئے کہ وہ ایسے نیک عمل کرے جن میں کسی قسم کا فساد نہ ہو.یعنی عمل اس کے نہ لوگوں کے
دکھلانے کے لئے ہوں، نہ اُن کی وجہ سے دل میں تکبر پیدا ہو کہ میں ایسا ہوں اور ایسا ہوں.اور
نہ وہ عمل ناقص اور نا تمام ہوں.اور نہ اُن میں کوئی ایسی بد بو ہو جو محبت ذاتی کے برخلاف ہو.لہ چاہئے کہ صدق اور وفاداری سے بھرے ہوئے ہوں اور ساتھ اس کے یہ بھی چاہئے کہ ہر
ایک قسم کے شرک سے پر ہیز ہو.نہ سورج ، نہ چاند، نہ آسمان کے ستارے، نہ ہوا، نہ آگ، نہ
523
Page 532
پانی ، نہ کوئی اور زمین کی چیز معبود ٹھہرائی جائے اور نہ دنیا کے اسباب کو ایسی عزت دی جائے
اور ایسا اُن پر بھروسہ کیا جائے کہ گویا وہ خدا کے شریک ہیں.اور نہ اپنی ہمت اور کوشش کو
کچھ چیز سمجھا جائے کہ یہ بھی شرک کے قسموں میں سے ایک قسم ہے.بلکہ سب کچھ کر کے یہ
سمجھا جائے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا.اور نہ اپنے علم پر کوئی غرور کیا جائے.اور نہ اپنے عمل پر
کوئی ناز.بلکہ اپنے تئیں فی الحقیقت جاہل سمجھیں اور کاہل سمجھیں اور خدا تعالیٰ کے آستانہ پر ہر
ایک وقت رُوح گری رہے اور دعاؤں کے ساتھ اس کے فیض کو اپنی طرف کھینچا جائے.اور
اس شخص کی طرح ہو جائیں کہ جو سخت پیاسا اور بے دست و پا بھی ہے اور اس کے سامنے ایک
چشمہ نمودار ہوا ہے نہایت صافی اور شیریں.پس اُس نے افتاں و خیزاں بہر حال اپنے تئیں اس
چشمہ تک پہنچادیا اور اپنی لبوں کو اس چشمہ پر رکھ دیا اور علیحدہ نہ ہوا جب تک سیراب نہ ہوا.لیکچر لاہور، روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 154)
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ
بِعِبَادَةِ رَبَّةٍ أَحَدًا.فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا عمل صالح سے یہاں یہ مراد ہے کہ اس میں کسی قسم کی بدی کی آمیزش نہ
ہو.صلاحیت ہی صلاحیت ہو.نہ جب ہو، نہ کبر ہو، نہ بخوت ہو، نہ تکبر ہو، نہ نفسانی اغراض کا کوئی حصہ
ہو، نہ رو مخلق ہو حتی کہ دوزخ اور بہشت کی خواہش بھی نہ ہو.صرف خدا کی محبت سے وہ عمل صادر
ہو.جب تک دوسری کسی قسم کی غرض کو دخل ہے تب تک ٹھوکر کھائے گا اور اس کا نام شرک ہے
کیونکہ وہ دوستی اور محبت کس کام کی جس کی بنیاد صرف ایک پیالہ چائے یا دوسری خالی محبوبات تک ہی
ہے.ایسا انسان جس دن اس میں فرق آتا دیکھے گا اسی دن قطع تعلق کر دے گا.جولوگ خدا سے اس
لئے تعلق باندھتے ہیں کہ ہمیں مال ملے یا اولاد حاصل ہو یا ہم فلاں فلاں امور میں کامیاب ہو جاویں
ان کے تعلقات عارضی ہوتے ہیں اور ایمان بھی خطرہ میں ہے.جس دن ان کے اغراض کو کوئی
صدمہ پہنچا اسی دن ایمان میں بھی فرق آجاوے گا.اس لئے پکا مومن وہ ہے جو کسی سہارے پر خدا کی
524
Page 533
عبادت نہیں کرتا.( البدر جلد 3 نمبر 34 مورخہ 8 ستمبر 1904 صفحہ 65)
مومن جب خدا سے محبت کرتا ہے تو الہی نور کا اس پر احاطہ ہو جاتا ہے اگر چہ وہ نور اس کو
اپنے اندر چھپالیتا اور اس کی بشریت کو ایک حد تک بھسم کر جاتا ہے جیسے آگ میں پڑا ہوالو ہا ہو
جاتا ہے لیکن پھر بھی وہ عبودیت اور بشریت معدوم نہیں ہو جاتی.یہی وہ راز ہے جو قل رائما آنا
بَشَر مثْلُكُمْ کی عہ میں مرکوز ہے.بشریت تو ہوتی ہے مگر وہ الوہیت کے رنگ کے نیچے
متواری ہو جاتی ہے اور اس کے تمام قومی اور اعضا للہی راہوں میں خدا تعالیٰ کے ارادوں سے
پر ہو کر اس کی خواہشوں کی تصویر ہو جاتے ہیں اور یہی وہ امتیاز ہے جو اس کو کروڑ بامخلوق کی روحانی
تربیت کا کفیل بنادیتا ہے اور ربوبیت تامہ کا ایک مظہر قرار دیتا ہے اگر ایسا نہ ہو تو کبھی بھی ایک
نبی اس قدر مخلوقات کے لئے بادی اور راہبر نہ ہو سکے.چونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کل
دنیا کے انسانوں کی روحانی تربیت کے لئے آئے تھے اس لئے یہ رنگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام
میں بدرجہ کمال موجود تھا اور یہی وہ مرتبہ ہے جس پر قرآن کریم نے متعدد مقامات پر حضور کی
نسبت شہادت دی ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے مقابل اور اسی رنگ میں آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کی صفات کا ذکر فرمایا ہے مَا اَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ (الانبیاء 108) اور ایسا ہی
فرما يا قُلْ يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا (الاعراف 159).رپورٹ جلسہ سالانہ 1897ء صفحہ 143)
حیہ کبھی نہ گمان کرنا چاہئے کہ حضرت مسیح یا دوسرے انبیاء ایک معمولی آدمی تھے.وہ اللہ
تعالیٰ کے برگزیدہ اور مقرب تھے.قرآن شریف نے مصلحت اور موقعہ کے لحاظ سے آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ایک لفظ اس قسم کا بیان فرمایا ہے کہ جہاں آپ کے بہت سے انوار
و برکات اور فضائل بیان کئے ہیں وہاں بشر مثلكم بھی کہہ دیا ہے.مگر یہ اس کے ہر گز معنے
نہیں ہیں کہ آنحضرت فی الواقع ہی عام آدمیوں جیسے تھے.اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ آپ کی شان
میں اس لئے استعمال فرمایا کہ دوسرے انبیاء کی طرح آپ کی پرستش نہ ہو اور آپ کو خدا نہ بنایا
525
Page 534
جاوے.اس سے یہ مراد ہر گز نہیں ہے کہ آپ کے فضائل و مراتب ہی سلب کر دئیے جاویں.الحکم جلد 8 نمبر 40 مورخہ 24 نومبر 1904ء صفحہ 2)
(ماخوذ از تفسیر حضرت مسیح موعود علیہ السلام )
حضرت خلیفہ امسیح الاول رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:
جس طرح حدیثوں میں یہ ثابت ہے کہ سورہ کہف کی ابتدائی آیتوں کا پڑھنا فتن
دجال سے نجات کا موجب ہے.اسی طرح آخری آیات کا پڑھنا بھی فتن دجال سے نجات کا
موجب ہے.اس لئے پھر غور کرو کہ جن کا سورہ کے ابتدا میں ذکر ہے انہی کا انتہا میں بھی ہے یا
نہیں؟ ان آیات سے ظاہر ہوتا ہے کہ دنبال کون ہے اور اس کے صفات کیا ہیں.( ضمیمه اخبار بدر قادیان 30 ر ا پریل، 5 رمئی 1910 ء صفحہ 162)
یہ سب آیات اشارہ کرتی ہیں کہ دجال ایک کاریگروں کی قوم کا نام ہے.66
ان کے اعمال کو ترازو میں تولنے کی ضرورت نہ ہوگی.سب کچھ اس دنیا میں لے چکے..(ضمیمه اخبار بدر قادیان 30 / اپریل، 5 رمئی 1910 ، صفحہ 162 ، 163)
(ماخوذ از حقائق الفرقان)
حضرت خلیفہ اسیح الثانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:
ملا یہ ان ہی لوگوں کا ذکر ہے جو حضرت مسیح کو نجات دہندہ اور خدا کا بیٹا مانتے ہیں.جن
کا ابتدائے سورۃ میں ذکر آیا تھا.وہ دنیا کو نفع پہنچانے کے لئے ایجادات کرنا ہی اپنی زندگی
کا مقصد سمجھتے ہیں.دین کی طرف توجہ نہیں.بلکہ اسے فضول سمجھتے ہیں.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ
ان کی بنائی ہوئی چیزوں کا نام و نشان باقی نہ رہے گا اور ہم قیامت کے دن ان کے لئے کوئی وزن
قائم نہ کریں گے.کیونکہ ان کے تمام اعمال دنیا کے لئے تھے نہ کہ آخرت کے لئے.ان قوموں
کی نگاہ میں الہی کلام اور اس کے رسولوں کی کوئی عزت نہ ہوگی.ایک انسان کو خدا بنا کر سب
نبیوں پر ہنسی اور تمسخر کریں گے.چنانچہ دیکھ لو کہ مسیحی لوگ مسیح کو خدا کا بیٹا قرار دینے کی وجہ سے
526
Page 535
سب انبیاء کی سخت ہتک کرتے ہیں اور ان کے وجود کو لغو اور فضول قرار دیتے ہیں اور شریعت
کولعنت بتاتے ہیں.جب ان پر عذاب آئے گا تو مومنوں کی ترقی کا وقت شروع ہوگا اور ان
کے صبر کا بدلہ ان کو مل جائے گا.اور اللہ تعالیٰ کے لئے اور اس کے دین کے لئے قربانیوں میں
ان کو ایسی لذت محسوس ہوگی کہ باوجود مال اور جان کی قربانیوں کے وہ اپنی حالت کو بدلنا پسند نہ
کریں گے.وہ لوگ دعوے کرتے ہیں کہ ہم نے یہ یہ ایجادات کی ہیں اور اتنے علوم دریافت کئے
ہیں اور کائنات کا راز دریافت کرنے کے قریب ہیں.فرماتا ہے.اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
توان سے کہہ دے ( یعنی اس زمانہ کے محمد رسول اللہ صلعم کے اتباع ان سے یوں کہہ دیں )
کہ تمہارا را ز کائنات کو دریافت کرنے کی کوشش کرنا ہمیشہ روزاؤل ہی رہے
گا اور باوجود اس قدر کوششوں کے تم کولہو کے بیل کی طرح وہیں کے وہیں کھڑے رہو گے
اور وہ قوتیں جواللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں پیدا کی ہیں ان میں سے اس قدر بھی دریافت نہ
کرسکو گے کہ جس قدرسمندر کے مقابل پر ایک قطرہ کی حیثیت ہوتی ہے.اس آیت میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ وہ تصانیف کا زمانہ ہوگا اور یہ قومیں سائنس
پر کثرت سے کتابیں لکھیں گی.ما ان سب پیشگوئیوں اور علوم غیبیہ کے بیان کرنے کے بعد فرماتا ہے کہ اے محمد
( صلی اللہ علیہ وسلم ) تو ان سے کہہ دے کہ میں تو اس قدر علوم سماویہ کے بتانے کے بعد بھی نہیں
کہتا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں یا خدائی صفات میرے اندر ہیں.میں تو صرف ایک بشر ہوں جس کی
ساری خوبی یہ ہے کہ اس پر اس کے رب نے اپنا کلام نازل فرمایا ہے.پس اگر تم بھی ان
انعامات کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو آؤ میری طرح موحد ہوجاؤ.اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے
مطابق عمل کرو.اور شرک چھوڑ دو.پھر دیکھو کہ اللہ تعالی کس طرح تم پر فضل کرتا ہے اور غیب
کے خزانے تمہارے لئے کھولتا ہے.رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جوکہف کی آخری دس آیات
527
Page 536
پڑھتا ہے دجال کے فتنہ سے محفوظ رہے گا.یہ بھی اس امر کا ثبوت ہے کہ دجال اور یا جوج
ماجوج سے مراد مسیحی فتنہ ہے.کیونکہ ان آیات میں اسی قوم کا ذکر ہے.جیسا کہ ہر انسان جوان
آیتوں کو سمجھ کر پڑھے معلوم کرسکتا ہے.(ماخوذ از تفسیر کبیر )
حضرت خلیفہ المسیح الثالث رحمہ اللہ خطبہ جمعہ فرمودہ 21 دسمبر 1979ء میں سورۃ الکہف کی
آیات 104 تا 107 کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں:
سورۃ کہف کی ان آیات میں دس باتیں بیان کی گئی ہیں.پہلی بات یہ ہے اللہ تعالیٰ
فرماتا ہے کہ تمہیں ان لوگوں کے متعلق بتائیں جو سب سے زیادہ گھاٹا پانے والے ہیں اپنے
اعمال کے لحاظ سے.انسان مختلف قسموں میں بٹ جاتے ہیں اپنے اعمال کے لحاظ سے.ایک
وہ ہیں جو خدا تعالیٰ کی معرفت رکھتے ہیں، ایک وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کا عرفان نہیں رکھتے ، ایک وہ
ہیں جو زندہ مذہب سے تعلق رکھنے والے ہیں، ایک وہ ہیں جن کا زندہ مذہب سے تعلق نہیں
ہوتا ، ایک وہ ہیں جو دنیوی لحاظ سے شریفانہ زندگی گزارتے ہیں اور ایک وہ ہیں جو دنیوی معیار
کے مطابق بھی بدزندگی گزارنے والے ہیں.ہر شخص اپنے رب سے اپنے اعمال کے مطابق
بدلہ پاتا اور جزا حاصل کرتا ہے اور وہ لوگ جو خدا تعالیٰ کے پیار کو حاصل کرنے میں کامیاب
ہوتے ہیں وہ بھی خدا تعالیٰ کے پیار کو اپنی قوتوں اور استعدادوں کے دائرہ کے اندر اپنی اس
سعی کے مطابق جو وہ اس دائرہ میں اپنے خدا کے حضور مقبول سعی کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں
اس کے مطابق وہ بدلہ پاتے ہیں.وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے ہیں وہ خدا تعالیٰ
کے غضب کو حاصل کرتے ہیں اور قہر کی آگ ان کے حصہ میں ہے لیکن ان میں بھی فرق
ہے.کسی پر اللہ تعالی کم غضب نازل کرتا ہے کسی پر زیادہ کرتا ہے.یہاں یہ مضمون اس بات سے شروع کیا گیا ہے کہ جوسب سے زیادہ گھاٹا پانے والے ہیں
ان کے متعلق ہم تمہیں کچھ بتانے لگے ہیں.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سب سے زیادہ گھاٹا پانے
والے اپنے اعمال کے لحاظ سے وہ ہیں کہ جو ایک تو خدا کو پہچانتے نہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان
528
Page 537
نہیں لاتے.دوسرے وہ جو خدا تعالیٰ کی طرف سے نشان ظاہر ہوتے ہیں ان کو پہچانتے نہیں
اور جس غرض سے وہ نشان ظاہر ہوتے ہیں وہ غرض ان کی نظر سے پوشیدہ رہتی ہے.بدقسمت
ہیں، وہ اس لئے کہ ان کی ساری توجہ، ان کی ساری کوشش، ان کا سارا عمل ان کا مقصود اور ان
کی ہمت جو ہے وہ اس دنیوی زندگی کے ساتھ تعلق رکھتی ہے.اس ورلی زندگی کو انہوں نے
اپنا مقصود بنالیا.دوسری بات یہاں اللہ تعالیٰ یہ بیان کرتا ہے ان آیات میں اس زندگی کو ورلی زندگی کو
انہوں نے اپنا مقصود بنالیا، اس کے لئے وہ عمل، کوشش سعی اور جہد کرتے ہیں اور پوری
توجہ کے ساتھ اور اپنی پوری طاقت کے ساتھ اور اپنی پوری ہمت کے ساتھ اس دنیا کو اور
صرف اس دنیا کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں.دنیا کے اموال کے حصول کے لئے
جائز و ناجائز میں کوئی تمیز نہیں کرتے.عزت کی خاطر، اپنی چودھراہٹ کی خاطر، اپنی بڑائی کی
خاطر وہ ظلم اور انصاف کی کوئی تمیز نہیں کرتے اور جب حقیقت بعض دفعہ سمجھتے بھی ہیں تو ان کی
عزت کی بیچ جو ہے اپنی ذاتی دنیوی لحاظ سے جو انہوں نے اپنا ایک وقار جھوٹا بنایا ہوا ہے اس
دنیا میں اس کی خاطر وہ حقیقت کو اور صداقت کو قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتے.اللہ
تعالیٰ فرماتا ہے کہ سب سے زیادہ گھاٹا پانے والے اپنے اعمال کے لحاظ سے وہ لوگ ہیں
جنہوں نے ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَوةِ الدُّنْيَا ورلی زندگی ہی کو اپنا مقصود بنالیا.اسی سے انہوں
نے غرض رکھی خدا کو بھول گئے جو خدا تعالیٰ نے آیات ظاہر کی تھیں ان کی اصلاح کے لئے اور
جو ہدایت بھیجی تھی مختلف انبیاء کے ذریعے مختلف زمانوں میں یہ اصولی بات یہاں بیان ہو رہی
ہے آدم سے لے کے قیامت تک اس کا بھی انہوں نے کوئی خیال نہیں کیا.بس دنیا ہے دنیا
ہے، کھانا ہے، پینا ہے، سونا ہے، ناچ ہے، گانا ہے، گپیں ہیں، چغلیاں ہیں، بدظنیاں ہیں،
اپنی بڑائی کی شیخی ہے، فخر کا اعلان ہے، اپنی جھوٹی عزتوں کی خاطر ہر قسم کا ظلم ہے وغیرہ وغیرہ
ہزار قسم کی برائیاں پھر ایسے شخص کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں چونکہ ہر قسم کی برائی ایسے شخص کے
اندر پیدا ہو جاتی ہے اس لئے سب سے زیادہ گھاٹا پانے والا وہ بن جاتا ہے.529
Page 538
اور پھر وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا اس کے ساتھ وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ اچھا
کام کر رہے ہیں.دنیا میں آگے نکل رہے ہیں.بین الاقوامی لیڈرشپ انہیں حاصل ہوگئی.بڑی طاقت ہے ایک دنیا کو دھمکی دیں تو آدھی دنیا لرز جاتی ہے کہ کہیں ہمارے اوپر کوئی آفت
ہی نہ آ جائے اور اس قسم کی فضا انہوں نے پیدا کی ہے کہ وہ اور ان کے ساتھی اسی چیز کو حسن عمل
سمجھتے ہیں جو حقیقی حسن عمل ہے اس سے وہ غافل ہیں.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ
يُحْسِنُونَ صُنعًا یہ تیسری بات تھی.اور چوتھی بات أُولَبِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَيْتِ رَبَّہم یہ اس لئے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات جو
ہیں اس کا یہ انکار کرتے ہیں.قرآن کریم کی اصطلاح میں آیات دو قسم کی ہیں.ایک وہ جو
دنیوی لحاظ سے خدا تعالیٰ کی صفات کے جلوے ظاہر ہوتے اور دنیا میں ان جلووں کے نتیجے میں
کچھ پیدا ہوتا ہے خلق یا امر کے نتیجے میں یعنی یا تو جو چیز پیدا ہوئی ہوئی ہے اس کی خاصیتوں میں.اضافہ کیا جاتا ہے.خدا تعالیٰ کے جلوے ان میں اضافہ کر کے ایک نئی چیز پیدا کرتے ہیں.بڑی کثرت کے ساتھ قرآن کریم نے آیات کے تحت اس قسم کے جلوے جو صفات باری کے
ہیں ان کا ذکر کیا ہے اور دوسری وہ آیات ہیں جو انبیاء کے ذریعہ سے اور انبیاء کے فیضان کے
نتیجہ میں ان کے متبعین کے ذریعہ سے انسان کی ہدایت کے لئے ، اس کی بہبود کے لئے ، اس
کی خوشحالی کے لئے اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لئے وہ آیات ظاہر کی جاتی ہیں.اس میں
سب سے آگے نکلنے والے ہمارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کے معجزات کا
انسان شمار نہیں کر سکتا اور وہ تمام باتیں معجزانہ رنگ میں جو ظاہر ہوئیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کے ذریعہ سے وہ بھی آیات ہیں.اسی واسطے جس طرح اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی کے
برسنے کا ذکر کرتے ہوئے اسے آیت شمار کیا اور اس پانی سے زمین کو زندہ کرنے کو اس نے
آیت کہا اور اس سے کھیتیاں اگانے کو اس نے آیت کہا اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے جو آیاتِ باری ہمارے سامنے پیش کیں کلام باری کی شکل میں یعنی قرآن کریم،
اس کے ہر ٹکڑے کو آیت کہا گیا.ساری آیات قرآنی ہیں نا.ہم گنتے ہیں کہ اس سورت کی اتنی
530
Page 539
آیات ہیں اس سورت کی اتنی آیات ہیں انہیں بھی آیات کہا جاتا ہے.تو یہ بنیادی طور پر
دو قسمیں ہیں قرآن کریم کی اصطلاح میں جن پر آیات کا لفظ بولا جاتا ہے.تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
کہ یہ الْأَخْسَرِينَ اعتمالا اس لئے ہیں کہ یہ انکار کرتے ہیں خدا تعالیٰ کی ان آیات کا جو
خدا تعالیٰ نے اس کائنات میں ظاہر کیں اس غرض سے کہ اس کے بندے ان آیات سے ہر قسم
کا فائدہ حاصل کریں اور جس غرض کے لئے انہیں پیدا کیا گیا ہے وہ وہاں تک پہنچیں.آیت کے جو بنیادی معنی ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک ایسی ظاہری علامت، جو کسی مخفی حقیقت کی
طرف انسان کو لے جاتی ہے تو یہ ساری آیات ایک بنیادی حقیقت کی طرف لے جانے والی
ہیں وہ اللہ تعالیٰ اور اس کی وحدانیت ہے.تو كَفَرُوا بِایت رم خدا تعالیٰ نے جس غرض سے
ان آیات کو نازل کیا تھا خواہ مادی دنیا میں جلوے ظاہر ہوئے اس کی صفات کے خواہ روحانی
دنیا میں جلوے ظاہر ہوئے اس کی صفات کے انہوں نے ان آیات کا انکار کیا اور پہچانا نہیں اور
جلوے اس لئے ظاہر ہوئے تھے کہ لقائے باری انسان کو حاصل ہو اور چونکہ انہوں نے آیات
ہی کو نہیں پہچانا ان کا انکار کیا.نہ مادی دنیا کی آیات سے نہ کائنات میں ظاہر ہونے والی
آیات سے جو خدا تعالیٰ کی طرف نشاندہی کرنے والی تھیں، ہمیں راستہ دکھانے والی تھیں خدا کی
وحدانیت کا نہ ان سے فائدہ اٹھایا نہ خدا تعالیٰ کا کلام جب نازل ہوا رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ
وسلم پر نہ اس سے فائدہ اٹھایا اور جس غرض سے یہ آیات نازل ہوئی تھیں کہ یہ ان کو بتایا جائے
کہ تم بے سہارا نہیں، تمہارا ایک سہارا ہے، تمہاری پیدائش کی ایک غرض ہے.تمہیں اس
لئے پیدا کیا گیا ہے کہ تمہارا اس ورلی زندگی میں بھی اپنے زندہ خدا سے ایک زندہ تعلق پیدا ہو.تو پانچویں بات ہمیں یہ بتائی کہ انہوں نے انکار کیا خدا تعالیٰ کی لقا سے یعنی وصلِ الہی اس دنیا
میں ممکن ہی نہیں.نہ آیات کو مانا اور پہچانا، نہ اس غرض سے واقف ہوئے اور اس کے لئے
کوشش کی جس غرض کے لئے ان پر دو قسم کی آیات کو نازل کیا گیا تھا.اس کا نتیجہ ظاہر ہے فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ چھٹی بات یہ ہے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے اعمال،
ان کی کوششیں ان کا مقصود جو تھا ان کا تعلق آسمانی رفعتوں کے ساتھ نہیں تھا.ان کا تعلق اس
531
Page 540
بات سے نہیں تھا کہ وہ اپنی زندگی اس رنگ میں گزاریں کہ خدا تعالیٰ کی محبت اور پیار کو حاصل
کرنے والے ہوں.زمین کی طرف وہ جھک گئے اور دنیا سے انہوں نے تسلی پالی اور ایک
عارضی خوشی جو تھی اس دنیا کی اسی کو سب کچھ سمجھ لیا اور ابدی خوشیوں کو اس عارضی خوشی پر قربان
کر دیا.حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ ان کے اعمال گر کر اسی دنیا کے ہو کر رہ گئے.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیکن صرف یہ زندگی تو نہیں.اس کے بعد ایک اور زندگی ہے اور اس کو
قرآن کریم کی اصطلاح میں قیامت کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے یعنی مرنے کے بعد نبی کریم صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ہے مَنْ مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِیامتہ کہ جو شخص انفرادی طور پر مرے اسی
وقت اس کی ایک قیامت ہو جاتی ہے لیکن ایک وہ ہے جب حشر ہوگا اور سارے اکٹھے کئے
جائیں گے اور خدا کا پیار حاصل کریں گے یا اس کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑے گا.اللہ تعالیٰ
فرماتا ہے کہ قیامت کے دن ان کے وہ اعمال جو دنیا کے لئے کئے گئے ہوں گے اور جن کے
نتیجہ میں خدا کے پیار کو حاصل کرنے کی کوئی کوشش نہیں ہوگی بے وزن ہوں گے ان کا کوئی
وزن نہیں ہوگا، بے نتیجہ ہوں گے ان کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، لا حاصل ہوں گے ان سے کچھ
حاصل نہیں ہوگا.زندگی کا مقصد تھا کہ خدا تعالیٰ کے عبد بنتے ، اس کے پیار کو حاصل کرتے،
ابدی جنتوں کے وارث بنتے وہ ان کے وارث نہیں بنیں گے.یہ ہے جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ یہ جہنم
ہے یعنی کہا کہ فَلا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيمَةِ وَزُنا قیامت کے دن ہمارا پیارا نہیں حاصل
نہیں ہوگا.ذلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ یہ جہنم ان کی جزا ہے اور اس لئے ہے کہ انہوں نے انکار
کیا آیات کا.خدا تعالیٰ نے جو دو قسم کی آیات جیسا کہ میں نے بتایا نازل کی تھیں انسان کی ہدایت کے
لئے ایک اپنے ان جلووں کے ذریعے جو اس نے کائنات میں کئے اور جن سے اس کی عظمت
ثابت ہوتی ہے، جن سے ہمیں یہ پتا لگتا ہے کہ خدا تعالیٰ کا اپنی مخلوق کے ہر ذرے کے ساتھ
ایک ذاتی اور ہمیشہ رہنے والا تعلق قائم ہے جس سے ہمیں پتا لگتا ہے کہ ایک لحظہ کے لئے اگر
532
Page 541
خدا تعالیٰ کا یہ قرب نہ ہو اس کی وقیوم کا تو فنا آ جائے اس چیز پر جس سے وہ قطع تعلق کرتا ہے.وہ
ہلاکت ہے وہ عدم بن جاتا ہے اس کے لئے.تو چونکہ انہوں نے کائنات میں ظاہر ہونے
والے جلووں کا انکار کیا اور جو روحانی ارتقاء کے لئے اور روحانی رفعتوں کے حصول کے لئے اور
اللہ تعالیٰ کے پیار کو حاصل کرنے کے لئے انبیاء علیہم السلام اور اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
کی بعثت ہوئی.نوع انسانی کے لئے صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ان کی بھلائی کے
لئے اب ایک زندہ نبی کی صورت میں قیامت تک انسانوں میں اپنے روحانی فیوض کے لحاظ سے
زندہ ہیں اور موجود ہیں.اس اتنی عظیم کتاب اتنی عظیم آیات جس کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ
انسان کو حیران کر دیتا ہے اتنی ہدایتیں، اتنی خوبصورتیاں ،حسن پاک کرنے کی اتنی طاقت، اتنا
جذب ان کے اندر ہے لیکن اس کو پہچانا نہیں انہوں نے.أَخْسَرِينَ احتمالا تو ثابت
ہو گیا.خدا کے نزدیک بدترین عمل کے لحاظ سے وہ لوگ ہیں کہ جو خدا تعالیٰ کی آیات کا انکار
کرتے ہیں جو ایت رسم ہے.خدا تعالیٰ نے اس لئے ان آیات کو ظاہر کیا تھا کہ ان کی
جسمانی اور روحانی تربیت کرے، ربوبیت کرے ربّ ہے وہ ان کا.اس لئے کیا تھا کہ وہ اس
کے نتیجہ میں اس کے پیار کو اس کی رضا کو اور اس کی رضا کی جنتوں کو حاصل کریں.ایک ابدی
جنت ان کے نصیب میں ہو جہاں خیر ہی وہ چاہیں گے اور ہر خیر جو وہ چاہیں گے وہ ان کو ملے
گی.بڑی عجیب ہے وہ دنیا جسے ہم آج سمجھ نہیں سکتے ہماری طاقت میں نہیں.آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ ہماری یہ آنکھ، نہ ہمارے یہ کان ، نہ ہمارا یہ دماغ اسے سمجھ سکتا
ہے لیکن تمثیلی زبان میں اشارے اس کی طرف کئے گئے ہیں.وہ اس کی حقیقت کو اس زندگی میں
اللہ تعالیٰ کے پیار کو جو وہاں جانے والے حاصل کریں گے ہر آن رفعتوں کے حصول کا ذکر
کر کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ دھندلا سا نقشہ اس زندگی میں بتایا ہے اور پھر یہاں پیار کر کے
بتایا ہے کہ اس زندگی میں جب میں پیار کرتا ہوں تمہاری امتحان کی ابتلا کی زندگی میں تمہاری
غلطیوں اور کوتاہیوں اور غفلتوں اور گناہوں کے باوجود جہاں ہر قسم کے گناہوں سے خدا تعالیٰ
533
Page 542
اپنے فضل کے ساتھ پاک کر کے بھیجے گا اس کا تو نقشہ ہی کچھ اور ہوگا.بہر حال یہ ان لوگوں کا
بیان ہے ان آیات میں جو اپنے اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ گرے ہوئے ہیں خدا تعالیٰ
کی نگاہ میں.( خطبات ناصر جلد هشتم 485-491)
اسی طرح آپ نے خطبہ جمعہ فرمودہ 19 مئی 1972ء میں فرمایا :
دنیا میں ایک وہ انسان ہے جو دنیا کے لئے دُنیا کماتا ہے اللہ تعالیٰ نے ایسےلوگوں
کے متعلق فرمایا ہے.ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَوةِ الدُّنْیا یعنی ان کی تمام تر کوشش اس دُنیوی
زندگی کے لئے ہوتی ہے.ان کے مقابلے میں ایک وہ انسان ہے جو دین کی خاطر اور
خدا تعالیٰ کی راہ میں اپنے اموال قربان کرنے کے لئے دُنیا کماتا ہے.اب جہاں تک دُنیا
کے کمانے کا سوال ہے.دونوں برابر ہیں لیکن جہاں تک دولت کے خرچ کرنے کا سوال ہے
ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے کیونکہ ایک تو دُنیا کما کر زمینی بن گیا اور دوسرے نے
دُنیا کمائی اور اس کے لئے آسمان کے دروازے کھول دئیے گئے.اس لئے ہر دو میں زمین
و آسمان کا فرق ہے.پس ربنا اتنا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً کی جب دُعا سکھائی گئی تو اس کے ایک معنے یہ ہوئے کہ
ہم خدا سے یہ کہیں کہ اے خدا! ہم نے انتہائی محنت اور انتہائی تدبیر کر دی دُنیا کمانے کے لئے
ہم نے اپنی تدبیر کو انتہا تک پہنچادیا اور اسی طرح دعا کو بھی انتہا تک پہنچادیا ہے اور اب اس
مقام پر کھڑے ہو کر ہم یہ کہتے ہیں رَبَّنَا اتنا في الدُّنْيَا حَسَنَةٌ کہ اے ہمارے رب! ہماری
تدبیر اور ہماری دُعا تیرے فضل اور تیری رحمت کے بغیر نتیجہ نہیں پیدا کر سکتی اس لئے تو اپنے
فضل سے اس کا نتیجہ پیدا کر اور اس دُنیا کی حسنات میں ہمیں شریک اور حصہ دار بنا اور ہمیں اس
کا وارث قرار دے تا کہ ہم دُنیا کی نعمتوں کو حاصل کر کے اور پھر ان نعمتوں کو تیری راہ میں
قربان کر کے اپنی روحانی اور اُخروی حسنات کے لئے سامان پیدا کریں.غرض حقیقت یہی ہے کہ دنیا کی حسنات کے بغیر اخروی حسنات مل نہیں سکتیں.میں اس کی
534
Page 543
.ایک مثال دے دیتا ہوں تا کہ نیچے بھی سمجھ جائیں.جو شخص دنیا کی حسنات سے کلی طور پر محروم ہو
جاتا ہے اس کے اوپر روحانی حکم لگتا ہی نہیں.اس کے متعلق لوگ کہہ دیتے ہیں کہ وہ پاگل
ہے.اس لئے جہاں تک ایک مجنون کی دُنیوی حسنات کے بارے میں محنت اور کمائی کا تعلق
ہے یا اس کی کوشش اور مجاہدہ کا سوال ہے وہ یہ کام کر ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ پاگل ہے.اس
لئے ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جسم اور زندگی بخشی.اللہ تعالیٰ نے اس کو بھائی
دئیے، اس کو دوست دئیے اور اس کے ارد گرد خیال رکھنے والے انسان بنائے.چنانچہ وہ اس کا
خیال رکھتے ہیں لیکن جہاں تک اس کی اپنی طاقتوں کا سوال ہے.اس کی کسی طاقت کے اوپر
کوئی حکم نہیں چلا سکتا.وہ اپنے جنون میں کسی آدمی کو قتل کر دیتا ہے تو حج کہتا ہے کہ پاگل تھا
اس سے قتل ہو گیا.ظلم ہو گیا لیکن اس کے اوپر کوئی الزام نہیں.پس جو شخص مجنون ہے اس
کے لئے دنیوی حسنات کی کمائی کے دروازے بند ہیں اور چونکہ دنیوی حسنات کی کمائی کے
دروازے اس کے لئے بند ہیں اسی لئے اُخروی حسنات کی کمائی کا دروازہ بھی اس کے لئے نہیں
کھولا جائے گا.پس ہم ایسے شخص کو مرفوع القلم کہہ دیتے ہیں.ہم اس پر نہ نیکی کاحکم لگاتے ہیں اور نہ بدی
کا ، نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس نے مالی قربانی دی اور نہ یہ کہ اُس نے مالی قربانی نہیں دی مثلاً اگر
کوئی مجنون یا مرفوع القلم آدمی اپنے باپ کی تجوری کو گھلا پائے اور وہاں سے دس ہزار روپے
نکال کر جنون کی حالت میں کسی مستحق کو دے دے تو یہ نیکی شمار نہیں ہو گی کیونکہ اس نے جنون
میں آ کر ایسا کیا ہے یہ نیکی نہیں جنون ہے.غرض یہ ایک حقیقت ہے اور قرآن کریم نے اسے بڑی وضاحت سے بیان کیا ہے کہ
ڈ نیوی حسنات کے بغیر اخروی حسنات کے سامان پیدا نہیں ہوتے ، اس لئے کہ اُخروی حسنات
کے سامان اللہ تعالیٰ کی راہ میں دُنیوی نعمتوں کو خرچ کرنے سے پیدا ہوتے ہیں.جس کے
پاس نعمت ہی کوئی نہیں وہ خرچ بھی نہیں کر سکتا.چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام
535
Page 544
نے فرمایا ہے کہ جو شخص نامرد ہے وہ پاک باز ہونے کا دعوی نہیں کرسکتا.کیونکہ اسے طاقت
ہی نہیں ہے.اللہ تعالیٰ نے انسان کو چار قسم کی طاقتیں اور صلاحتیں بخشی ہیں اور ان کے اوپر
اُخروی نعمتوں کا انحصار ہے، یہ طاقتیں ماں ہیں اُخروی نعمتوں کے حصول کی ، ان کے بغیر کوئی
اُخروی نعمت نہیں مل سکتی.حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے مما رَزَقْنَهُمْ يُنْفِقُونَ( البقرة 4) اور بعض
دوسری آیتوں کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت سی طاقتیں اور
صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں اور ہر طاقت اور صلاحیت سے یہ مطالبہ فرمایا ہے کہ وہ میری راہ میں
قربان ہو جائے.خطبات ناصر جلد چہارم صفحه 221 تا223)
اسی طرح حضرت خلیفہ امسیح الثالث نے خطبہ جمعہ فرمودہ 18 اپریل 1977ء میں فرمایا:
ہم اس دنیا میں انسان کو جو کچھ بھی ملتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ملتا ہے اور یہ عطا
ایک خاص مقصد کے لئے انسان پر نازل ہوتی ہے.انسان کا ذہن ہے، انسان کی طاقت
ہے، انسان کی استعداد ہے، اخلاقی طاقتیں اور روحانی قوتیں ہیں جو انسان کو دی گئی ہیں.غرضیکہ انسان کو جو کچھ بھی ملا ہے وہ ایک خاص مقصد کی خاطر اسے ملا ہے.اللہ تعالیٰ نے ان دو آیات میں جن کی میں نے ابھی تلاوت کی ہے فرمایا ہے انسان میں سے
دو گروہ بن جاتے ہیں.ایک وہ گروہ ہے کہ جو کچھ انہیں ملتا ہے اسے وہ صرف مَتَاعُ الحيوة
الدُّنْيَا وَزِينتها سمجھتے ہیں اور اس سے آگے نہیں بڑھتے.خدا نے جو دنیوی سامان دیتے ہیں
ان کا استعمال محض دنیا کے لئے اور دنیا کی اغراض کی خاطر کیا جاتا ہے.خدا تعالیٰ کی عطا کو دنیا کی
زینت کے لئے سمجھا جاتا ہے.اسی کی طرف دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے اشارہ کرتے ہوئے
فرما ياضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا -
پھر فرمایا ایک دوسرا گروہ ہے جو عقل رکھتا ہے اور اس کا استعمال کرتا ہے اس گروہ کے
متعلق تو خدا تعالیٰ نے فرمایا آفَلا تَعْقِلُونَ یہ لوگ عقل سے کام کیوں نہیں لیتے لیکن عقل سے
536
Page 545
.کام لینے والوں کا بھی ایک گروہ ہے اور وہ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں جو کچھ انسان کو ملا وہ اس
لئے ہے کہ وہ اپنے وجود اور اس کی طاقتوں کی نشو نما اس طرح کرے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس
کا سچا، حقیقی اور پختہ تعلق قائم ہو جائے.یہی تعلق ہے جس کے نتیجہ میں اس دنیا کے بعد بھی حسین
جنتوں کا وعدہ دیا گیا ہے اور یہی تعلق ہے جس کے نتیجہ میں اس دنیا میں بطور جزا کے اللہ تعالیٰ کی
طرف سے بدلہ ملتا ہے.فرمایا وَمَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ اور وہ بدلہ خیر اور بھلائی ہوتی ہے.وہ دکھوں
کی طرف، وہ جہنم کی طرف اور وہ خدا تعالیٰ کے غضب کی طرف لے جانے والی چیز نہیں ہوتی
بلکہ خیر محض ہوتی ہے، خدا کا عطیہ ہوتی ہے اور صرف اس دنیا میں ختم نہیں ہو جاتی.خدا تعالیٰ
انسان کو اس کے نیک اعمال کے نتیجہ میں اور اس کی جو قر بانیاں اور ایثار ہے اور خدا کے لئے
محبت ذاتی کی انسان کے دل میں جو تڑپ ہوتی ہے اس کے نتیجہ میں انسان کو جو کچھ ملتا ہے وہ
خیر بھی ہے وابقی اور باقی رہنے والی چیز بھی ہے یعنی اس دنیوی زندگی پر موت آجانے کے
بعد وہ ختم نہیں ہو جاتی بلکہ باقی رہتی ہے انسان کو ایک نئی زندگی ایک جنتی زندگی ملتی ہے اور اس
میں وہ ہمیشہ کے لئے خدا تعالیٰ کے فضلوں کو حاصل کرتا اور اس کی رضا سے انتہائی مسرتوں کو
پاتا ہے.خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ گروہ جو خدا تعالیٰ کے لئے خدا ہی کی عطا کردہ دنیوی چیزیں خرچ
کرتا ہے، وہ اس یقین پر قائم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے وہ ضرور ملے گا.فرمایا
وَعْدًا حَسَنًا بڑا حسین وعدہ ہے وہ حسین بھی ہے اور پورا ہونے والا بھی ہے کیونکہ خدا تعالیٰ
فرماتا ہے لا يُخلف الميعاد خدا کے جو وعدے اور وعید ہیں ہر دو مشروط ہیں اور ہر دو اپنی شرائط
کے ساتھ پورے ہوتے ہیں.اسی لئے انسان کو خاتمہ بالخیر کی دعا کی تحریک کی گئی ہے.خَيْرٌ و ابقی ہی کے الفاظ کے بعد خدا تعالیٰ نے ان آیات میں فرمایا تم عقل سے کام کیوں
نہیں لیتے تم سمجھتے کیوں نہیں کہ تمہاری پیدائش کی غرض کیا ہے، تم سمجھتے کیوں نہیں کہ جو کچھ
تمہیں ملا ہے وہ اسی مقصد کے حصول کے لئے تمہیں ملا ہے.قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ
خدا نے فرما یا خَيْرُ وَ أَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَ عَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (شوری 37) فرمایا خدا تعالیٰ
537
Page 546
کے حکم کے مطابق اور اس کی ہدایت کی روشنی میں جولوگ اپنے اموال کو اور اپنی طاقتوں کو اپنی
قوتوں اور استعدادوں کو اور اپنی اخلاقی اور روحانی صلاحیتوں کو اجا گر کرتے اور خدا تعالیٰ کی
ہدایت کے مطابق خداداد قوتوں کی نشو ونما کرتے ہیں وہ عقل سے کام لینے والے ہیں اور یہی وہ
لوگ ہیں جو ایمان لائے وَ عَلَى رَبِّهِمُ يَتَوَكَّلُونَ یعنی انہوں نے اپنی انتہائی کوشش کی
خدا تعالیٰ کے قرب کے حصول میں مگر نتائج کو اللہ تعالیٰ کے فضلوں پر چھوڑ دیا.دراصل ایمان
کے معنے عقیدہ کا ایمان اور زبان سے اس کا اقرار اور اس کے مطابق عمل کرنا یہ سب چیزیں
لغت عربی کے مطابق لفظ ایمان میں شامل ہیں.تو جو شخص ایمان لاتا اور مومنانہ زندگی گزارتا
ہے اور اس کے دل میں پاکیزگی پائی جاتی ہے اور کھوٹ نہیں اور ملاوٹ نہیں اور نفاق نہیں اور
فساد نہیں ہوتا اور اعمالِ صالحہ بجالاتا ہے اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ
وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہی کافی نہیں ، جب تک خدا تعالیٰ اپنے فضل اور رحمت سے خاتمہ بالخیر نہ کرے
اور اپنے فضل اور رحمت سے جنتوں کے سامان نہ پیدا کرے محض اعمال کوئی چیز نہیں...چنانچہ
صحیح جہت کی طرف سائنس کی ہر ترقی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ مخلوق خدا انسان کی ایک نئی شکل میں
خدمت کر رہی ہے.ہر سائنسی انکشاف (Scientific Discovery) سے پتہ لگتا ہے کہ
کتنا عظیم اعلان تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں فرمایا تھا.وَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا
فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ (الجانيه 14) لیکن پھر بھی ان سائنسدانوں میں سے ایک گروہ ایسا ہے
جو عقل سے کام نہیں لیتے اور اس دنیا کے متاع اور اس کی زینت کو کافی سمجھتے ہیں اور بجائے اس
کے کہ اس دنیوی متاع اور اس کی زینت کے نتیجہ میں اخروی متاع کے سامان پیدا کرنے
کے لئے اور اُخروی زندگی کے حسن کے حصول کے لئے کوشش کرتے ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي
الحيوة الدنیا دنیوی عیش و آرام میں پڑ جاتے ہیں جو کہ وقتی ہے اور اس میں حقیقی لذت بھی
نہیں مگر پھر بھی ایسے لوگ اپنا سب کچھ دنیوی لذتوں کی خاطر برباد کر دیتے ہیں اور خدا سے
ڈوری کی راہیں ان کو خدا کے غضب کی جہنم کی طرف لے جاتی ہیں لیکن وہ لوگ بھی ہیں جو عقل
رکھتے ہیں اور جو اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس شریعت پر جو محمد رسول اللہ
538
Page 547
صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے ہاتھ میں دی ہے، ایمان لائے ہیں اور جن کی زندگیاں اسلام
کی خاطر ہیں.( خطبات ناصر جلد ہفتم صفحہ 65 تا 69)
اسی طرح خطبہ جمعہ فرمودہ 12 جولائی 1968ء میں غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا
الضالین کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا:
ضال سیدھے راہ سے بھٹکنے والے کو کہتے ہیں اور قرآن کریم نے اس کے یہ معنی کئے
ہیں کہ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَوةِ الدُّنْيَا پس ضالین وہ ہیں جن کی تمام کوششیں ان
راہوں کی تلاش میں رہتی ہیں جو اخروی زندگی سے ورے ورے ختم ہوتی جاتی ہے.ضَل
سَعْيُهُمْ في الحیوۃ الدنیا وہ اس ورلی زندگی کے کناروں سے نکل کر اُخروی زندگی تک نہیں
پہنچتیں.راہ بھٹک جاتی ہے کوشش جو ہے وہ آگے چل ہی نہیں سکتی ایسے راستے وہ اختیار
کرتے ہیں جن کا صرف اس دنیا سے تعلق ہے حالانکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں (خواہ
وہ قوتیں اور استعدادیں ہوں یا مادی سامان ہوں یا فطرت کے تقاضے ہوں ) اس لئے دی
تھیں کہ اس دنیا میں وہ ختم نہ ہوں نہ صرف اس دنیا سے ان
کا تعلق ہو بلکہ ان کے نتیجہ میں انسان
اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کی جنت کو حاصل کرے اور اس دنیا میں بھی وہ اس رضا کی جنت
کو حاصل کرے لیکن ایک گروہ انسانوں میں سے یا بعض افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جوان قوتوں
کی انتہا اس دنیا کے ورے ورے سمجھتے ہیں اسی طرح دنیا کے جو سامان ہیں ان کے متعلق سمجھتے
ہیں کہ وہ بس دنیا میں ہی ہمارے کام آئیں گے حالانکہ ایک عقلمند مومن یہ جانتا ہے کہ وہ بکرا جو
خدا نے مجھے دیا ہے اور جو گوشت پوست ہے اور اس کی زندگی بھی چھوٹی ہے ایک ایسی چیز
ہے جو صرف اس دنیا میں ہمارے کام نہیں آسکتی بلکہ اگر ہم چاہیں تو یہ اس دوسری دنیا میں بھی
ہمارے کام آئے گی کیونکہ اگر ہم چاہیں تو تقویٰ کا ٹیگ لیبل اس کے ساتھ لگا دیں تو بکرا یہاں
رہ جائے گا لیکن وہ ٹھیک، وہ لیبل آسمانوں کے خدا کے پاس پہنچ جائے گا.لَن ينال الله
539
Page 548
لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ (الحج 38) تقویٰ کے ساتھ لگا تو بکرا اللہ
کے حضور پہنچ گیا اور تمہارے لئے دوسری زندگی میں بھی مفید ہو گا ( یہ زندگی تو اس زندگی کے
مقابلہ میں اتنی معمولی چیز ہے کہ ہم اس کا نام ہی نہیں لیں گے ) دوسری زندگی میں بھی وہ کام
آجائے گا.آپ دفتر میں جاتے ہیں سو روپیہ آپ کو تخوا ہلتی ہے اب کوئی احمق ہی کہہ سکتا ہے
کہ یہ چاندی کے سکے یا کاغذ کے نوٹ صرف اس دنیا سے تعلق رکھتے ہیں قیصر کی چیز ہے اس
کا ایک حصہ اس کو دے دینا چاہئے لیکن چونکہ یہ خدا کی چیز نہیں اسے نہیں دینا چاہئے.اگر کوئی
ایسا سمجھتا ہے تو وہ تباہ ہو جائے گا.اسے یہ کہنا چاہئے کہ ہر چیز چونکہ خدا کی ہے اس لئے جس قدر
چاہے وہ لے لے پھر جو بچ جائے گا وہ میں استعمال کرلوں گا.ایک مومن کی یہی نیت ہوتی ہے
اس کی یہ نیت نہیں ہوتی کہ جو مجھ سے بچ جائے گا وہ میں خدا کو دے دوں گا بلکہ اس کی نیت یہ
ہوتی ہے کہ جو بچ جائے گا اس معنی میں وہ کہے کہ میں نے اتنالے لیا باقی تم استعمال کرلو تو پھر وہ
میں استعمال کرلوں گا.نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے بعض کے ساتھ یہی
سلوک کیا آپ نے فرمایا نہیں اتنا مال نہیں چاہئے واپس لے جاؤ اور استعمال کرو.اس نے
نیک نیتی کے ساتھ جتنا دینا چاہا پیش کر دیا اور ہمیں یقین ہے کہ اس نے خدا سے اسی کے مطابق
ثواب حاصل کر لیا.نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حالات کو دیکھتے ہوئے اور اسلام کی
اس وقت کی ضرورتوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہا سارے مال کی ضرورت نہیں واپس لے جاؤ.پھر یہ بتانے کے لئے کہ جب ایک مومن خدا کے حضور اپنا سارا مال پیش کرتا ہے تو اس کے
دل میں یہ بدنیتی نہیں ہوتی کہ سارا مال قبول نہیں کیا جائے گا اس لئے سارا مال پیش کرنے
میں کوئی حرج نہیں.حضرت ابوبکرؓ نے جب اپنا سارا مال پیش کیا تو وہ سارا قبول کر لیا گیا اور
بتایا گیا کہ ہر مومن کے دل کی یہی کیفیت ہے لیکن کچھ مومن وہ ہوتے ہیں جو جواں ہمت
ہوتے ہیں اور جو انتہائی بوجھ برداشت کر سکتے ہیں ( چنانچہ آپ نے ان میں سے ایک کا سارا
مال لے لیا اور مثال کو قائم کر دیا ) اور کچھ وہ ہوتے ہیں کہ ان کی روح تو انتہائی قربانیاں دینے
540
Page 549
کے لئے تیار ہوتی ہے لیکن ان کا ماحول اور ان کا جسم اس کے لئے تیار نہیں ہوتا ان کوفتنہ اور
امتحان سے بچانے کے لئے ان کے مال کا ایک حصہ قبول کر لیا جاتا ہے اور ایک حصہ واپس کر دیا
جاتا ہے.پس مومن کی مادی کوشش دنیا میں حدود سے ورے ختم نہیں ہو جاتی اور اس کے متعلق
نہیں کہا جاسکتا کہ ضَلَّ سَعْيُهُمُ في الحيوةِ الدُّنْيَا کیونکہ روپیہ وہ خرچ کرتے ہیں زندگی کا
ہرلمحہ جو وہ گزارتے ہیں اخلاق کا ہر مظاہرہ ان سے سرزد ہوتا ہے بچوں سے محبت اور پیار کا
سلوک جو دنیا ان سے دیکھتی ہے اس کے پیچھے یہی روح کام کر رہی ہوتی ہے کہ جس نے خدا کی
رضا کے لئے اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالا اس نے بھی ثواب حاصل کر لیا.غرض مومن اپنے ہر
دنیوی کام کو اخروی جزا اور اخروی نعماء کے حصول کا ذریعہ بنالیتا ہے اور اس کے متعلق نہیں
کہا جا سکتا ہے کہ وہ ضَلَّ سَعْيُهُمْ في الحیوۃ الدنیا والے گروہ میں ہے.خطبات ناصر جلد دوم صفحہ 212 تا 214)
حضرت خلیفہ امسیح الثالث رحمہ اللہ نے جلسہ سالانہ 1974ء کے موقع پر 28 دسمبر کو اپنے
اختتامی خطاب میں فرمایا:
قرآن کریم نے محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کا ہم سے کیا تعارف کروایا ہے.محمد صلی اللہ
علیہ وسلم پر ہمارا کیا ایمان ہے.قرآن کریم نے ایک ہی وقت میں ہمیں دو باتیں بتائی ہیں
ایک طرف ہمیں یہ کہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں دیگر جو بشر ہیں ان کی طرح چنانچہ فرمایا :
قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَى أَنَّمَا الهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ
عَمَلًا صَالِحًا وَ لَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا مساوات انسانی کا ایک بڑا ہی عظیم نعرہ چودہ سو
سال پہلے لگایا گیا اس وقت تک انسان نے اس کی عظمت اور اس کی حقیقت کو نہیں سمجھا.ہم
حیران ہوتے ہیں کہ اپنے آپ کو بڑے بڑے عقلمند کہنے والے انسانی مساوات کی حقیقت اور
اس کی تعریف کو سمجھتے ہی نہیں.محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا انسان نہ کسی ماں نے ویسا بچہ جنا اور نہ
جن سکتی ہے اتنی عظمتوں والے انسان کے منہ سے قرآن کریم نے یہ کہلوا يا قل انما انا بشر
541
Page 550
مثلكم یہ اسلام کی صداقت کی ایک بڑی دلیل ہے میں نے 1970ء میں اس سے فائدہ
اٹھایا اور تقریروں میں اسے بیان کرتا رہا.ایک جگہ کچھ پادری منہ بنا کے بیٹھے ہوئے تھے اس
ملک کالاٹ پادری بھی وہاں تھا تو وہاں پر مجھے خیال آیا کہ ان کو اسلام سے تعارف تو کراؤں
چنانچہ میں نے اپنی تقریر میں کہا کہ محمدصلی اللہ علیہ وسلم جو پیرا ماؤنٹ پرافٹ ہیں ( میں نے ان
کی زبان کا محاورہ لیا ) ان کی زبان سے خدا نے یہ کہلوا یا قُل إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ کہ بشر ہونے
کے لحاظ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تم افریقن میں کوئی فرق نہیں تو وہ جو آپ کے نائب اور
جونئیر قسم کے انبیاء تھے جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسی علیہ السلام گذرے ہیں
انہیں اور ان کے متبعین کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے آپ کو تم سے بڑا سمجھیں.اس پر وہ پادری
یوں اچھلے انہوں نے کہا کہ یہ کیا بم شیل ہمارے اوپر گرا دیا ہے پس نعرے لگانا اور چیز ہے اور
حقیقت کو سمجھ کر اپنی زندگی اور معاشرہ کو اس کے مطابق ڈھالنا یہ بالکل اور چیز ہے تو نبی اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایک حقیقت قرآن کریم نے یہ بیان کی ہے اور قرآن کریم نے
ہمارے محبوب آقانبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایک دوسری حقیقت یہ بیان کی کہ قد
جَاءَكُمْ مِنَ اللهِ نُورُ ( المائدة (16) اور آپ کو ستراجًا منيرا (الاحزاب (47) کہا یعنی
ایک چمکتا ہوا سورج اور کہا کہ آپ مظہر اتم الوہیت ہیں اور جو کامل نور ہے جو کامل طور پر دنیا کو
روشن کرنے والا سورج ہے اس کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ مظہر اتم الوہیت ہو.اور جو مظہر
اتم الوہیت ہے اس کے لئے یہ ضروری ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے اس کے متعلق یہ اعلان
ہو کہ لَوْلاكَ لَمَا خَلَقْتُ الأفلاك ( موضوعات کبیر زیر حرف لام ).یہ دو حقیقتیں ہیں جو ایک ہی وجود میں پائی جاتی ہیں اور نوع انسانی نے ان حقائق مقام
محمدیت سے دو مختلف فائدے اٹھائے ہیں قُلْ إِنما انا بشرٌ مِثْلُكُمْ کہ بشر ہونے کے لحاظ
سے
مجھ میں اور تم میں کوئی فرق نہیں یہ اعلان کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اُسوہ کی
شکل میں بنی نوع انسان کے سامنے پیش کیا گیا ہے کیونکہ اگر یہ ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
بشر نہیں بلکہ سپر مین (super man) ہیں اور بشر سے کوئی بلند و بالا چیز ہیں تو انسان کہتا کہ
542
Page 551
میں عاجز انسان ایک ایسی ہستی کی جو بشر سے کہیں بالا ہے، پیروی کیسے کر سکتا ہوں وہ میرے
لئے اُسوہ کیسے بن سکتی ہے تو بشر کہہ کے آپ کو اُسوہ بنایا اور نور کہہ کے آپ کو خاتم الانبیاء بنایا
کیونکہ کامل نور مظہر اتم الوہیت ہے ویسے اصل نور تو اللہ ہے اللهُ نُورُ السَّمَوتِ وَالْأَرْضِ
(النور (36) لیکن اللہ کے بعد مخلوق میں سے جو کامل نور کی حیثیت سے دنیا کی طرف آیا وہ خاتم
الانبیاء ہے اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بشر ہونے کے لحاظ سے مختلف ہے بشر کے
مقام کے نتیجہ میں آپ اسوہ بنے اور نور ہونے کے لحاظ سے آپ ایک طرف مظہر اتم الوہیت
بنے اور دوسری طرف لَوْلاكَ لَمَا خَلَقْتُ الافلاك ( موضوعات کبیر زیر حرف لام) کی
صداقت انسان کے سامنے رکھی گئی نور ہونے کی حیثیت سے آدم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم
الا نبیاء سے نور حاصل کیا لیکن بشر ہونے کے لحاظ سے چونکہ آپ نے اس دنیا میں زندگی بعد
میں گذاری اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام کے لئے اسوہ تو نہیں بن سکتے تھے.آدم نے تو آپ کی شان دیکھی ہی نہیں ہزاروں سال کے بعد آپ کی پیدائش ہوئی لیکن بعد
میں آنے والی امت کے لئے بشر ہونے کے لحاظ سے آپ اُسوہ ہیں اور یہ اُسوہ قیامت تک
کے لئے ہے اور نور ہونے کے لحاظ سے لَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الْأَفَلَاكَ کا نعرہ لگایا گیا اور اس
سارے جہان میں جہاں بھی ہمیں نور نظر آتا ہے انسان کے اندر یا دوسری مخلوق میں وہ
محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء کے طفیل نظر آتا ہے.انبیاء نے بھی نور نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
کے نور سے حاصل کیا اور ذہنوں نے نور فراست بھی وہیں سے حاصل کیا اور درختوں نے
نور روئیدگی بھی وہیں سے حاصل کیا اور گھوڑے اور بیل اور یہ جو جانور ہیں انہوں نے نورِ خدمت
بھی وہیں سے حاصل کیا اس لئے کہ یہ جو آپ کا مقام نور ہونے کا ہے اس کے نتیجے میں آپ کو
لولاك لما خَلَقْتُ الأفلاك ( موضوعات کبیر زیر حرف لام) کہا گیا جس کا مطلب یہ ہے کہ
اس کا ئنات کا منصو بہ اللہ تعالیٰ نے اس لئے بنایا کہ وہ محمدصلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء اور اپنے
بعد نور کامل کے طور پر پیدا کرنا چاہتا تھا اگر حضرت خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی
نے کامل نور انسانی یعنی انسان بھی اور کامل نور بھی، نہ بنایا ہوتا تو یہ کائنات نہ بنائی جاتی اور اگر یہ
543
Page 552
کائنات نہ پیدا کی جاتی تو پھر نہ درختوں کا نور ہوتا ، نہ حسینوں کے حسن کا نور نہ کام کرنے کے
حسن عمل کانور، نہ نبیوں کا نور.یا مقربین الہی کا نور کوئی نور ہوتا ہی نہ.تو اس کائنات کی تخلیق کا
منصو بہ نور ہے یہ نور ہے.جس کے متعلق انسان کو کہا گیا کہ وہ تمہیں بلاتا ہے تم لبیک کہتے
ہوئے اس کی طرف دوڑ و کیونکہ وہ تمہیں اس لئے بلاتا ہے کہ تمہیں زندگی دے اور اس کائنات
میں جو سب سے حسین نور اور سب سے اچھا نور ہمیں نظر آتا ہے وہ زندگی کا نور ہے یعنی وہ نور جو
الحى القیوم کے ساتھ وابستگی کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے.تو اللہ تعالی نے آپ کو خاتم الانبیاء
بنایا اور اس کے نتیجے میں یہ نور کا مقام ہے خاتم الانبیاء مقام کا نور کامل کا مقام ہے اور آدم سے
لے کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک اگر ایک لاکھ بیس ہزار نبی آئے تو ایک لاکھ بیس ہزار نبی
نے اور اگر دوسروں کے نزدیک ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی آئے تو ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی
نے اس نور سے نور لیا اور خاتم الانبیاء کے نتیجہ میں آدم نبی بنے اور نوع نبی بنے اور موسی نبی بنے
اور عیسی نبی بنے اور ابراہیم علیہم السلام نبی بنے اگر اس کائنات میں یہ نور نہ ہوتا یعنی
پلینڈ (planned) نہ ہوتا اس کا منصوبہ نہ ہوتا تو نہ آدم کی ضرورت تھی نہ نوح کی نہ ابراہیم کی نہ
موسی کی نہ عیسی علیہم السلام کی.کسی کی بھی ضرورت نہیں تھی.پہلوں نے بھی خاتم الانبیاء سے نور
لیا اور انہوں نے خدا تعالیٰ کی محبت کو حاصل کیا اور بعد میں آنے والوں نے بھی قیامت تک
محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء سے نور لیا یا لیں گے اور خدا تعالیٰ کے قرب کے مدارج ان کو
ملیں گے تو ایک لاکھ بیس ہزار آ گیا اور ایک کے اوپر اعتراض پیدا ہو گیا.یہ جو خاتم الانبیاء کا
مقام ہے اس کے متعلق آپ نے فرمایا یہ میرا استدلال نہیں ہے بلکہ آپ نے فرمایا ہے کہ
میں خاتم النبیین تھا اور ابھی آدم پیدا نہیں ہوا تھا اس کا وجود مٹی کے ذروں میں گم ہوا ہوا تھا اور
مٹی کے ذروں کے ساتھ رُل رہا تھا اور مجھے اس وقت خدا تعالیٰ نے خاتم الانبیاء بنادیا تھا یہ
بات تو واضح ہے کہ خاتم الانبیاء کا مقام بشر کا مقام نہیں ہے خاتم الانبیاء کا مقام نور کا مقام ہے،
سراج منیر کا مقام ہے جس طرح چاند ہے یا جو سورج کے گردگھو منے والے ستارے ہیں وہ چاند
اور وہ ستارے سورج سے نور لے کر اپنا نور ظاہر کرتے ہیں اسی طرح پہلوں نے بھی محمد صلی اللہ
544
Page 553
علیہ وسلم خاتم الانبیاء کے نور سے نور لیا اور وہ دنیا میں چمکے اور بعد میں آنے والوں نے بھی آپ
ہی کے نور سے نور لیا یعنی ہر قسم کا قرب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہی حاصل ہوتا ہے
صدیق بھی نہیں بن سکتے جب تک آپ سے نور نہ لیں اور شہید یا صالح بھی نہیں بن سکتے جب
تک یہ نور نہ حاصل کریں ان سے بھی جو کم ہیں یعنی چھوٹے سے چھوٹا پیار بھی خدا سے حاصل نہیں
کر سکتے جب تک کہ اس نور کی جھلک ان کے اندر پیدا نہ ہو تب اللهُ نُورُ السَّمَوتِ وَالْأَرْضِ
(النور (36) اپنی کچھ مشابہت دیکھ کر یعنی اس نور کی جومحمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل حاصل کیا
ہوتا ہے اپنے پیار اور محبت کا سلوک کرتا ہے.یہ ہے ہمارا یمان اور یہ ہے ہمارا عقیدہ
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ، کہ ایک ہی وقت میں آپ بشر بھی ہیں اور نور بھی ہیں.نور کے
متعلق میں نے ذرا تفصیل سے بتایا ہے اور بشر کے متعلق میں نے مختصر بتایا ہے لیکن بہر حال یہ
ایک حقیقت ہے کہ اُسوہ بننے کے لئے سپر (super) کی ضرورت نہیں تھی.کوئی بن ہی نہیں
سکتا.انسان انسان کے لئے اُسوہ بن سکتا ہے اور بشر بشر کے لئے اسوہ بن سکتا ہے.فرشتے
بشر کے لئے اسوہ نہیں بن سکتے.تو خدا نے آپ کو بشر بنایا اور قرآن کریم نے آپ کی وفات کا
ذکر کیا.شعراء روئے کہ ہماری آنکھوں کا نور تو تھا.شاعر بھٹک بھی جاتا ہے اور یہاں بھی شاعر
بھٹکا کہ میری آنکھوں کا نور تو تھا.اب میرے لئے دنیا اندھیر ہو گئی ہے.یہ درست ہے کہ یہ
جذبات کا اظہار ہے اور بڑا پیارا اظہار ہے لیکن آنکھوں
کا نور تو ہم سے علیحدہ نہیں ہوا.وہ تو
جب سے دنیا بنی ہے وہ نور اس دنیا، اس کا ئنات کے ساتھ لگا ہوا ہے سب سے پہلا نبی جو دنیا
کی طرف آیا اس نے بھی اس نور سے حصہ لیا.وہ نور دنیا سے کس طرح علیحدہ ہو گیا، لیکن یہ
ٹھیک ہے کہ بشر کا جو وجود تھا اس کے لحاظ سے کچھ عرصے کے بعد وفات ہوگئی لیکن بنی نوع
انسان کے لئے اتنا عظیم اُسوہ آپ نے چھوڑا ہے.بنی نوع انسان تو جب تک مانے نہیں
فائدہ نہیں اٹھا سکتے.آپ نے اپنے متبعین، امت محمدیہ کے لئے اتنا عظیم اسوہ چھوڑا ہے کہ
انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے.بشر کے لحاظ سے بھی ہم آپ کی ذات اپنے تصور میں لائیں یا
نور اور سراج منیر کے لحاظ سے آپ کی ذات اپنے تصور میں لائیں بے اختیار ہمارے منہ سے
545
Page 554
نکلتا ہے اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ
546
خطابات ناصر جلد دوم صفحہ 80 تا 84)
Page 555
XXXXXXXXXXXXX
سورة حم السجدة - آيات 31 تا 37
إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا 31.وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب
تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَيْكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا ہے پھر مستقل مزاجی سے اس عقیدہ پر قائم ہو
گئے اُن پر فرشتے اُتریں گے یہ کہتے ہوئے کہ
تَحْزَنُوا وَاَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِى كُنتُمْ ڈرو نہیں اور کسی پچھلی غلطی کا غم نہ کرو اور اس
تُوعَدُونَ
جنت کے ملنے سے خوش ہو جاؤ جس کا تم سے
وعدہ کیا گیا تھا.نَحْنُ اَوْلِيَؤُكُمْ فِي الْحَيَوةِ الدُّنْيَا وَفِي 32.ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست ہیں اور آخرت
الْآخِرَةِ ۚ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي
میں بھی تمہارے دوست رہیں گے اور اس (جنت)
أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَدَّعُوْنَ
نُزُلًا مِنْ غَفُوْرٍ رَّحِيْمِن
میں جو کچھ تمہارے جی چاہیں گے تم کو ملے گا اور جو کچھ
تم مانگو گے وہ بھی تم کو اس میں ملے گا.33.یہ بخشنے والے ( اور ) بے انتہا کرم کرنے
والے خدا کی طرف سے مہمانی کے طور پر ہوگا.وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللهِ 34.اور اس سے زیادہ اچھی بات کس کی ہوگی جو
کہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے اور اپنے ایمان
وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ
الْمُسْلِمِينَ
فرمانبرداروں میں سے ہوں.کے مطابق عمل کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو
وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعُ 35.اور نیکی اور بدی برابر نہیں ہوسکتی.اور تو برائی
بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ کا جواب نہایت نیک سلوک سے دے.اس کا نتیجہ
عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ
یہ ہوگا کہ وہ شخص کہ اس کے اور تیرے درمیان
عداوت پائی جاتی ہے وہ تیرے حسن سلوک کو دیکھ
کر ایک گرم جوش دوست بن جائے گا.547
Page 556
وَمَا يُلَقَّهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا ۚ وَمَا 36.اور ( باوجود ظلموں کے سہنے کے) اس (قسم کے
سلوک) کی توفیق صرف انہی کو ملتی ہے جو بڑے صبر کرنے
يُلَقَّهَا إِلَّا ذُو حَظِّ عَظِيمٍ
والے ہیں اور یا پھر ان کوملتی ہے جن کو ( خدا کی طرف سے
نیکی کا) ایک بہت بڑا حصہ ملا ہو.وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَنِ نَزْغٌ 37.اور اگر شیطان ( یعنی حق سے دور ہستی ) تجھے
ط
فَاسْتَعِدُ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ
الْعَلِيمُ
تکلیف پہنچائے تو ( فوراً اس کا بدلہ لینے کے لئے
تیار نہ ہو جایا کر بلکہ ) اللہ سے پناہ مانگا کر ( کہ وہ
تجھے اس ادنی درجہ کے خلق سے بچائے) اللہ یقیناً
بہت سننے والا ( اور ) بہت جاننے والا ہے.548
Page 557
اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلِئِكَةُ
أَلا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَابِهِرُ وا بِالْجَنَّةِ الَّتِى كُنتُمْ تُوعَدُونَ
حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں:
جولوگ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ جلشانہ ہے پھر اپنی ثابت قدمی دکھلاتے ہیں کہ کسی
مصیبت اور آفت اور زلزلہ اور امتحان سے اُن کے صدق میں ذرہ فرق نہیں آتا اُن پر فرشتے
اُترتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ تم ذرہ خوف نہ کرو اور نہ غمگین ہو اور اس بہشت کے تصور سے
شادان اور فرحان رہو جس کا تمہیں وعدہ دیا گیا ہے ہم تمہارے متولی اور تمہارے پاس ہر وقت
حاضر اور قریب ہیں کیا دُنیا میں اور کیا آخرت میں.( آئینہ کمالات اسلام، روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 98)
جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر استقامت اختیار کی ان کی یہ نشانی ہے
کہ ان پر فرشتے اترتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ تم مت ڈرو اور کچھ غم نہ کرو اور خوشخبری سنو اس
بہشت کی جس کا تمہیں وعدہ دیا گیا تھا ہم تمہارے دوست اور متوئی اس دنیا کی زندگی میں ہیں
اور نیز آخرت میں اور تمہارے لئے اس بہشت میں وہ سب کچھ دیا گیا جو تم مانگو یہ مہمانی ہے
غفور رحیم سے.اب دیکھتے اس آیت میں مکالمہ الہیہ اور قبولیت اور خدا تعالیٰ کا متولی اور متکفل ہونا اور اسی
دنیا میں بہشتی زندگی کی بناڈالنا اور ان کا حامی اور ناصر ہونا بطور نشان کے بیان فرمایا گیا.( جنگ مقدس، روحانی خزائن جلد 6 صفحہ 145 146)
وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور باطل خداؤں سے الگ ہو گئے پھر
استقامت اختیار کی.یعنی طرح طرح کی آزمائشوں اور بلا کے وقت ثابت قدم رہے.ان پر
549
Page 558
فرشتے اترتے ہیں کہ تم مت ڈرو اور مت غمگین ہو اور خوش ہوا اور خوشی میں بھر جاؤ کہ تم اس خوشی
کے وارث ہو گئے جس کا تمہیں وعدہ دیا گیا ہے.ہم اس دنیوی زندگی میں اور آخرت میں
تمہارے دوست ہیں.اس جگہ ان کلمات سے یہ اشارہ فرمایا کہ استقامت سے خدا تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے.یہ سچ بات ہے کہ استقامت فوق الکرامت ہے.کمال استقامت یہ ہے کہ چاروں طرف
بلاؤں کو محیط دیکھیں اور خدا کی راہ میں جان اور عزت اور آبرو کو معرض خطر میں پاویں اور کوئی
تسلی دینے والی بات موجود نہ ہو یہاں تک کہ خدا تعالیٰ بھی امتحان کے طور پر تسلی دینے والے
کشف یا خواب یا الہام کو بند کر دے اور ہولناک خوفوں میں چھوڑ دے.اس وقت نامردی نہ
دکھلاویں اور بزدلوں کی طرح پیچھے نہ ہٹیں.اور وفاداری کی صفت میں کوئی خلل پیدا نہ کریں.صدق اور ثبات میں کوئی رخنہ نہ ڈالیں.ذلت پر خوش ہو جائیں.موت پر راضی ہو جائیں اور
ثابت قدمی کے لئے کسی دوست کا انتظار نہ کریں کہ وہ سہارا دے.نہ اس وقت خدا کی بشارتوں
کے طالب ہوں کہ وقت نازک ہے اور باوجود سراسر بے کس اور کمزور ہونے کے اور کسی تسلی
کے نہ پانے کے سیدھے کھڑے ہو جائیں اور ہر چہ بادا باد کہہ کر گردن کو آگے رکھ دیں اور
قضا و قدر کے آگے دم نہ ماریں اور ہر گز بے قراری اور جزع فزع نہ دکھلاویں جب تک کہ
آزمائش کا حق پورا ہو جائے.یہی استقامت ہے جس سے خدا ملتا ہے.یہی وہ چیز ہے جس کی
رسولوں اور نبیوں اور صدیقوں اور شہیدوں کی خاک سے اب تک خوشبو آ رہی ہے.( اسلامی اصول کی فلاسفی ، روحانی خزائن جلد 10 صفحہ 420،419)
جولوگ خدا پر ایمان لا کر پوری پوری استقامت اختیار کرتے ہیں.ان پر خدائے
تعالیٰ کے فرشتے اترتے ہیں.اور یہ الہام ان کو کرتے ہیں کہ تم کچھ خوف اور غم نہ کرو.تمہارے لئے وہ بہشت ہے جس کے بارے میں تمہیں وعدہ دیا گیا ہے.سو اس آیت میں بھی
صاف لفظوں میں فرمایا ہے کہ خدا تعالیٰ کے نیک بندے غم اور خوف کے وقت خدا سے الہام
پاتے ہیں اور فرشتے اتر کر ان کی تسلی کرتے ہیں.لیکن اس جگہ یادر ہے کہ الہام کے لفظ سے
550
Page 559
اس جگہ یہ مراد نہیں ہے کہ سوچ اور فکر کی کوئی بات دل میں پڑ جائے جیسا کہ جب شاعر شعر کے
بنانے میں کوشش کرتا ہے یا ایک مصرع بنا کر دوسرا سو چتا رہتا ہے تو دوسرا مصرع دل میں
پڑتا ہے.سو یہ دل میں پڑ جانا الہام نہیں ہے بلکہ یہ خدا کے قانون قدرت کے موافق اپنی فکر اور
سوچ کا ایک نتیجہ ہے.جو شخص اچھی باتیں سوچتا ہے یا بری باتوں کے لئے فکر کرتا ہے اس کی
تلاش کے موافق کوئی بات ضرور اس کے دل میں پڑ جاتی ہے.ایک شخص مثلاً نیک اور
راستباز آدمی ہے جو سچائی کی حمایت میں چند شعر بناتا ہے اور دوسراشخص جو ایک گندہ اور پلید
آدمی ہے اپنے شعروں میں جھوٹ کی حمایت کرتا ہے اور راستبازوں کو گالیاں نکالتا ہے تو
بلا شبہ یہ دونوں کچھ نہ کچھ شعر بنا لیں گے بلکہ کچھ تعجب نہیں کہ وہ راستبازوں کا دشمن جو جھوٹ کی
حمایت کرتا ہے بباعث دائمی مشق کے اس کا شعر عمدہ ہو.سوا گر صرف دل میں پڑ جانے کا نام
الہام ہے تو پھر ایک بدمعاش شاعر جور است بازی اور راست بازوں کا دشمن اور ہمیشہ حق کی
مخالفت کے لئے قلم اٹھاتا اور افتراؤں سے کام لیتا ہے خدا کا ملہم کہلائے گا.دنیا میں ناولوں
وغیرہ میں جادو بیانیاں پائی جاتی ہیں اور تم دیکھتے ہو کہ اس طرح سراسر باطل مگر مسلسل مضمون
لوگوں کے دلوں میں پڑتے ہیں.پس کیا ہم ان کو الہام کہہ سکتے ہیں؟ بلکہ اگر الہام صرف دل
میں بعض باتیں پڑ جانے کا نام ہے تو ایک چور بھی ملہم کہلا سکتا ہے کیونکہ وہ بسا اوقات فکر کر کے
اچھے اچھے طریق نقب زنی کے نکال لیتا ہے اور عمدہ عمدہ تدبیریں ڈاکہ مارنے اور خون ناحق
کرنے کی اس کے دل میں گزر جاتی ہیں تو کیا لائق ہے کہ ہم ان تمام نا پاک طریقوں کا نام
الہام رکھ دیں؟ ہر گز نہیں.بلکہ یہ ان لوگوں کا خیال ہے جن کو اب تک اس سچے خدا کی خبر نہیں
جو آپ خاص مکالمہ سے دلوں کو تسلی دیتا اور نا واقفوں کو روحانی علوم سے معرفت بخشتا ہے.الہام کیا چیز ہے؟ وہ پاک اور قادر خدا کا ایک برگزیدہ بندہ کے ساتھ یا اس کے ساتھ جس کو
برگزیدہ کرنا چاہتا ہے ایک زندہ اور باقدرت کلام کے ساتھ مکالمہ اور مخاطبہ ہے.سو جب یہ
مکالمہ اور مخاطبہ کافی اور تسلی بخش سلسلہ کے ساتھ شروع ہو جائے اور اس میں خیالات فاسدہ کی
551
Page 560
تاریکی نہ ہواور نہ غیر متنی اور چند بے سر و پا لفظ ہوں اور کلام لذیذ اور پر حکمت اور پُر شوکت ہو تو وہ
خدا کا کلام ہے جس سے وہ اپنے بندہ کو تسلی دینا چاہتا ہے اور اپنے تئیں اس پر ظاہر کرتا ہے.ہاں
کبھی ایک کلام محض امتحان کے طور پر ہوتا ہے اور پورا اور بابرکت سامان ساتھ نہیں رکھتا.اس میں خدا تعالیٰ کے بندہ کو اس کی ابتدائی حالت میں آزمایا جاتا ہے تا وہ ایک ذرہ الہام کا
مزہ چکھ کر پھر واقعی طور پر اپنا حال و قال سے ملہموں کی طرح بناوے یا ٹھو کر کھاوے.پس اگر
وہ حقیقی راستبازی صدیقوں کی طرح اختیار نہیں کرتا تو اس نعمت کے کمال سے محروم رہ جاتا ہے
اور صرف بیہودہ لاف زنی اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے.کروڑ ہا نیک بندوں کو الہام ہوتا رہا ہے
مگر ان کا مرتبہ خدا کے نزدیک ایک درجہ کا نہیں بلکہ خدا کے پاک نبی جو پہلے درجہ پر کمال
صفائی سے خدا کا الہام پانے والے ہیں وہ بھی مرتبہ میں برابر نہیں.( اسلامی اصول کی فلاسفی، روحانی خزائن جلد 10 صفحه 437تا439)
حمد جو لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور پھر استقامت اختیار کرتے ہیں فرشتے ان کو
بشارت کے الہامات سناتے رہتے ہیں اور ان کو تسلی دیتے رہتے ہیں جیسا کہ حضرت موسیٰ
علیہ السلام کی ماں کو بذریعہ الہام تسلی دی گئی.لیکن قرآن ظاہر کر رہا ہے کہ اس قسم کے
الہامات یا خوابیں عام مومنوں کے لئے ایک روحانی نعمت ہے خواہ وہ مرد ہوں یا عورت
ہوں.اور ان الہامات کے پانے سے وہ لوگ امام وقت سے مستغنی نہیں ہو سکتے.اور اکثریہ
الہامات ان کے ذاتیات کے متعلق ہوتے ہیں اور علوم کا افاضہ ان کے ذریعہ سے نہیں ہوتا اور
نہ کسی عظیم الشان تحدی کے لائق ہوتے ہیں اور بہت سے بھروسے کے قابل نہیں ہوتے بلکہ
بعض وقت ٹھو کر کھانے کا موجب ہو جاتے ہیں.اور جب تک امام کی دستگیری افاضہ علوم نہ
کرے تب تک ہر گز ہر گز خطرات سے امن نہیں ہوتا.اس امر کی شہادت صدر اسلام میں ہی
موجود ہے.کیونکہ ایک شخص جو قرآن شریف کا کا تب تھااس کو بسا اوقات نور نبوت کے
قرب کی وجہ سے قرآنی آیت کا اس وقت میں الہام ہو جا تا تھا جبکہ امام یعنی نبی علیہ السلام وہ
آیت لکھوانا چاہتے تھے.ایک دن اس نے خیال کیا کہ مجھ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
552
Page 561
میں کیا فرق ہے.مجھے بھی الہام ہوتا ہے.اس خیال سے وہ بلاک کیا گیا.اور لکھا ہے کہ قبر
نے بھی اس کو باہر پھینک دیا.جیسا کہ بلغم بلاک کیا گیا.( ضرورة الامام ، روحانی خزائن جلد 13 صفحہ 473)
خدا تعالیٰ کو اپنا متولی اور متکفل سمجھنا اور پھر لازمی امتحانوں اور آزمائشوں سے متزلزل
نہ ہونا اور مستقیم الاحوال رہنا بھی خوف اور حزن کا علاج ہے.(مکتوبات احمد جلد دوم صفحه 24،23)
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور استقامت کی ، ان پر
فرشتے اترتے ہیں.اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ دل کو صاف کرتے ہیں اور نجاست اور
گندگی سے، جو اللہ سے دُور رکھتی ہے، اپنے نفس کو دور رکھتے ہیں ان میں سلسلہ الہام کے لئے
ایک مناسبت پیدا ہو جاتی ہے.سلسلہ الہام شروع ہو جاتا ہے.......پھر فرمایا و ابشروا
بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ یعنی تم اس جنت کے لئے خوش ہو جس کا تم کو وعدہ ہے.رپورٹ جلسہ سالانہ 1897 صفحہ 36)
م اسلام کی حقیت اور حقانیت کی اوّل نشانی یہی ہے کہ اس میں ہمیشہ ایسے راستباز جن
سے خدا تعالیٰ ہمکلام ہو پیدا ہوتے ہیں.تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَئِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا
سو یہی معیار حقیقی سچے اور زندہ اور مقبول مذہب کی ہے اور ہم جانتے ہیں کہ یہ نور صرف صرف
اسلام میں ہے دوسرے مذاہب اس روشنی سے بے نصیب ہیں.الحکم جلد 5 نمبر 19 مورخہ 24 مئی 1901 ، صفحہ 4)
الهام یعنی وحی الہی ایسی شے ہے کہ جب تک خدا سے پوری صلح نہ ہو اور اس کی اطاعت کے
لئے اس نے گردن نہ رکھ دی ہو تب تک وہ کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی.خدا تعالیٰ قرآن شریف میں
فرماتا ہے اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزِّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَئِكَةُ إِلَّا تَخَافُوا وَلَا
تَحْزَنُوا وَابْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ یہ اس امر کی طرف اشارہ ہے.نزول وحی کا صرف
ان کے ساتھ وابستہ ہے جو کہ خدا کی راہ میں مستقیم ہیں اور وہ صرف مسلمان ہی ہیں.( البدر جلد 4 نمبر 8 مورخہ 13 مارچ 1905 ، صفحہ 2)
553
Page 562
اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا کہ نَحْنُ اَولِيَؤُكُمْ فِي الْحَيَوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ کہ ہم اس
دنیا میں بھی اور آئندہ بھی متقی کے ولی ہیں.سو یہ آیت بھی تکذیب میں ان نادانوں کی ہے جنہوں
نے اس زندگی میں نزول ملائکہ سے انکار کیا.اگر نزع میں نزولِ ملائکہ تھا تو حیات الڈ نیا میں
خدا تعالیٰ کیسے ولی ہوا.رپورٹ جلسہ سالانہ 1897 ، صفحہ 38،37)
وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر انہوں نے استقامت اختیار کی یعنی اپنی
بات سے نہ پھرے اور طرح طرح کے زلازل ان پر آئے مگر انہوں نے ثابت قدمی کو ہاتھ سے
نہ دیا.ان پر فرشتے اترتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ تم کچھ خوف نہ کرو اور نہ کچھ حزن اور اس بہشت
سے خوش ہو جس کا تم وعدہ دیئے گئے تھے یعنی اب وہ بہشت تمہیں مل گیا اور بہشتی زندگی اب
شروع ہوگئی.کس طرح شروع ہوگئی نَحْنُ اولیو كُم الخ اس طرح کہ ہم تمہارے متولی اور
متکفل ہو گئے اس دنیا میں اور آخرت میں اور تمہارے لئے اس بہشتی زندگی میں جو کچھ تم مانگو
وہی موجود ہے یہ غفور رحیم کی طرف سے مہمانی ہے.مہمانی کے لفظ سے اس پھل کی طرف
اشارہ کیا ہے جو آیت تُؤتي أكلها كُلّ حِينٍ ( ابراھیم 26) میں فرمایا گیا تھا.جنگ مقدس ، روحانی خزائن جلد 6 صفحه 126)
جولوگ اللہ ( جلشانہ) کے دوست ہیں یعنی جو لوگ خدائے تعالیٰ سے سچی محبت رکھتے
ہیں اور خدا تعالیٰ ان سے محبت رکھتا ہے تو ان کی یہ نشانیاں ہیں کہ نہ ان پر خوف مستولی ہوتا ہے
کہ کیا کھائیں گے یا کیا پئیں گے یا فلاں بلا سے کیوں کر نجات ہوگی کیونکہ وہ تسلی دیئے جاتے
ہیں.اور نہ گزشتہ کے متعلق کوئی حزن و اندوہ ہوتا ہے کیونکہ وہ صبر دیئے جاتے ہیں.دوسری یہ نشانی ہے کہ وہ ایمان رکھتے ہیں یعنی ایمان میں کامل ہوتے ہیں اور تقویٰ اختیار کرتے
ہیں.یعنی خلاف ایمان و خلاف فرمانبرداری جو باتیں ہیں اُن سے بہت دُور رہتے ہیں.تیسری اُن کی یہ نشانی ہے کہ انہیں ( بذریعہ مکالمہ الہیہ ورویائے صالحہ بشارتیں ملتی رہتی
ہیں) اس جہان میں بھی اور دوسرے جہان میں بھی خدا تعالیٰ کا ان کی نسبت یہ عہد ہے جوٹل
554
Page 563
نہیں سکتا اور یہی پیارا درجہ ہے جو انہیں ملا ہوا ہے.یعنی مکالمہ الہیہ اور رویائے صالحہ سے
خدا تعالیٰ کے مخصوص بندوں کو جو اس کے ولی ہیں ضرور حصہ ملتا ہے اور ان کی ولایت کا بھاری
نشان یہی ہے کہ مکالمات و مخاطبات الہیہ سے مشرف ہوں ( یہی قانونِ قدرت اللہ جل شانہ کا
ہے ) کہ جولوگ ارباب متفرقہ سے منہ پھیر کر اللہ جل شانہ کو اپنا رب سمجھ لیں اور کہیں کہ ہمارا
تو ایک اللہ ہی رب ہے ( یعنی اور کسی کی ربوبیت پر ہماری نظر نہیں ) اور پھر آزمائشوں کے
وقت میں مستقیم رہیں ( کیسے ہی زلزلے آویں، آندھیاں چلیں، تاریکیاں پھیلیں ان میں ذرا
تزلزل اور تغیر اور اضطراب پیدا نہ ہو پوری پوری استقامت پر رہیں ) تو ان پر فرشتے اترتے
ہیں ( یعنی الہام یا رویائے صالحہ کے ذریعہ سے انہیں بشارتیں ملتی ہیں ) کہ دنیا اور آخرت میں
ہم تمہارے دوست اور متوئی اور متکفل ہیں اور آخرت میں جو کچھ تمہارے جی چاہیں گے وہ
سب تمہیں ملے گا.یعنی اگر دنیا میں کچھ مکروہات بھی پیش آویں تو کوئی اندیشہ کی بات نہیں کیونکہ
آخرت میں تمام غم دور ہو جائیں گے اور سب مراد یں حاصل ہوں گی.اگر کوئی کہے کہ یہ کیوں کر ہوسکتا ہے کہ آخرت میں جو کچھ انسان کا نفس چاہے اس کو
ملے.میں کہتا ہوں کہ یہ ہونا نہایت ضروری ہے اور اسی بات کا نام نجات ہے.ورنہ اگر انسان
نجات پا کر بعض چیزوں کو چاہتا رہا اور ان کے غم میں کباب ہوتا اور جلتا رہامگر وہ چیزیں اس کو
نہ ملیں تو پھر نجات کا ہے کی ہوئی.ایک قسم کا عذاب ساتھ ہی رہا.لہذا ضرور ہے کہ جنت یا
بهشت یا مکتی خانہ یا سورگ جو نام اس مقام کا رکھا جائے جو انتہا سعادت پانے کا گھر ہے وہ
ایسا گھر چاہیے کہ انسان کو مین گل الوجوہ اس میں مصفا خوشی حاصل ہو اور کوئی ظاہری یا باطنی
رنج کی بات درمیان نہ ہو اور کسی نا کامی کی سوزش دل پر غالب نہ ہو.ہاں یہ بات سچ ہے کہ بہشت میں نالائق اور نامناسب باتیں نہیں ہوں گی.مگر مقدس دلوں
میں اُن کی خواہش بھی پیدا نہ ہوگی بلکہ ان مقدس اور مطہر دلوں میں جو شیطانی خیالات سے
پاک کئے گئے ہیں، انسان کی پاک فطرت اور خالق کی پاک مرضی کے موافق پاک خواہشیں
555
Page 564
پیدا ہوں گی.تا انسان اپنی ظاہری اور باطنی اور بدنی اور روحانی سعادت کو پورے پورے طور پر
پالیوے اور اپنے جمیع قومی کے کامل ظہور سے کامل انسان کہلاوے.کیونکہ بہشت میں داخل
کرنا انسانی نقش کے مٹا دینے کی غرض سے نہیں جیسا کہ ہمارے مخالف عیسائی و آریہ خیال
کرتے ہیں بلکہ اس غرض سے ہے کہ تا انسانی فطرت کے نقوش ظاہر و باطناً بطور کامل چمکیں
اور سب بے اعتدالیاں دور ہو کر ٹھیک ٹھیک وہ امور جلوہ نما ہو جائیں جو انسان کے لئے بلحاظ
ظاہری و باطنی خلقت اس کی کے ضروری ہیں.ایک عیسائی کے تین سوال اور اُن کے جوابات، روحانی خزائن جلد 4 صفحہ 479 تا 481 حاشیہ)
وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي
بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِى حَمِيمٌ
جو شخص شرارت سے کچھ یاوہ گوئی کرے تو تم نیک طریق سے صلح کاری کا اس کو جواب
دو تب اس خصلت سے دشمن بھی دوست ہو جائے گا.اسلامی اصول کی فلاسفی ، روحانی خزائن جلد 10 صفحه 349)
اگر کوئی تجھ سے نیکی کرے تو تو اس سے زیادہ نیکی کر اور اگر تو ایسا کرے گا تو مابین
تمہارے اگر کوئی عداوت بھی ہوگی تو وہ ایسی دوستی سے بدل جائے گی کہ گویا وہ شخص ایک
دوست بھی ہے اور رشتہ دار بھی.لیکچر لاہور، روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 156 )
تعلیم اس لئے تھی کہ اگر دشمن بھی ہو تو وہ اس نرمی اور حسن سلوک سے دوست بن
جاوے اور ان باتوں کو آرام اور سکون کے ساتھ ٹن لے.لیکچر لدھیانہ، روحانی خزائن جلد 20 صفحه 275)
تقویٰ کے بہت سے اجزاء ہیں.عُجب ، نخود پسندی، مال حرام سے پر ہیز اور بداخلاقی
سے بچنا بھی تقویٰ ہے.جو شخص اچھے اخلاق ظاہر کرتا ہے.اس کے دشمن بھی دوست ہو جاتے
ہیں.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ اب خیال فرمائیے یہ ہدایت کیا تعلیم دیتی
556
Page 565
ہے؟ اس ہدایت میں اللہ تعالیٰ کا یہ منشاء ہے کہ اگر مخالف گالی دے تو اس کا جواب گالی سے نہ
دو بلکہ صبر کرو.اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ تمہاری فضیلت کا قائل ہو کر خود ہی نادم اور شرمندہ ہوگا اور
ی سزا اس سزا سے کہیں بڑھ کر ہوگی جو انتقامی طور پر تم اس کو دے سکتے ہو.یوں تو ایک ذرا سا
آدمی اقدام قتل تک نوبت پہنچا سکتا ہے لیکن انسانیت کا تقاضا اور تقویٰ کا منشاء یہ نہیں ہے.خوش اخلاقی ایک ایسا جوہر ہے کہ موذی سے موذی انسان پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے.کیا اچھا
کہا ہے کہ ع
لطف کن لطف که بیگانه شود حلقه بگوش
حضرت خلیفۃ المسیح الاوّل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:
رپورٹ جلسہ سالانہ 1897 ، صفحہ 83)
جو لوگ ایمان کو مشروط کرتے ہیں وہ محروم رہ جاتے ہیں.اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی
پرواہ نہیں کرتا.ہاں خدا تعالیٰ کسی کو خالی نہیں چھوڑتا.جو اس کی راہ میں صدق و ثبات سے قدم
رکھتا ہے وہ بھی اس قسم کے انعامات سے بہرہ وافر لے لیتا ہے.جیسے فرمایا الَّذِينَ قَالُوا
رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَئِكَةُ - جن لوگوں نے اپنے قول و فعل سے بتایا
کہ ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہے.پھر انہوں نے اس پر استقامت دکھائی.ان پر فرشتے نازل
ہوتے ہیں.اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ نزولِ ملائکہ سے پہلے دو باتیں ضروری ہیں.ربنا اللہ کا
اقرار اور اس پر صدق و ثبات اور اظہار استقامت.ایک نادان سُنت اللہ سے ناواقف ان مراحل کو تو طے نہیں کرتا اور امید رکھتا ہے اس مقام
پر پہنچنے کی جواُن کے بعد واقع ہے.یہ کیسی غلطی اور نادانی ہے.اس قسم کے شیطانی وسوسوں سے بھی الگ رہنا چاہئے.خدا تعالیٰ کی راہ میں استقامت اور
عجز کے ساتھ قدم اٹھاؤ.قومی سے کام لو.اس کی مدد طلب کرو.پھر یہ کوئی بڑی بات نہیں
557
Page 566
ہے کہ تم بھی اللہ تعالیٰ کے فضل کے وارث ہو جاؤ اور حقیقی رؤیا اور الہام سے حصہ پاؤ.الحكم 17 مئی 1905ء صفحہ 6، 22 فروری 1905ء)
تقویٰ کا ابتدا دعا، خیرات اور صدقہ سے ہے اور آخر ان لوگوں میں شامل ہونے سے
ہے جن کی نسبت فرمایا ہے.اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا جن لوگوں نے کہا
کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر استقامت دکھلائی.( بدر 13 دسمبر 1906، صفحہ 9)
نیکی کی تحریک کے لئے ملائکہ بڑی نعمت ہیں وہ انسان کے دل میں نیکی کی تحریک
کرتے ہیں.اگر کوئی ان کے کہنے کو مان لے تو اس طبقہ کے جو ملائکہ ہیں وہ سب اس کے
دوست ہو جاتے ہیں.قرآن مجید میں فرمایا.نَحْنُ اَوْلِيَاءُ كُمْ فِي الْحَيَوةِ الدُّنْيَا (حم السجده32) ایسی پاک
مخلوق کسی کی دوست ہو اور کیا خواہش ہو سکتی ہے.(احکم 7 ، 14 جولائی 1911 ، صفحہ 6)
انسان
کو بیٹھے بیٹھے کبھی نیک اور کبھی ہدارا دے پیدا ہو جاتے ہیں.یہ کیوں ہوتے ہیں.جبکہ کوئی کام بڑوں اسباب اور علمل کے نہیں ہوتا تو نیک اور بد ارادے کی تحریک کیوں
ہوئی ؟ اس تحریک کو ہماری شریعت میں فرشتہ کہتے ہیں.ہم اسی پر قناعت کرتے اور نیکی کے
محرک کا نام فرشتہ رکھتے ہیں.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ملائکہ وشیاطین کو ہر وقت انسان کے دل سے
تعلق رہتا ہے اور موقعہ پر تحریکیں کرتے ہیں.اگر وہ تحریک نیکی کی ہے تو فرشتہ کی طرف سے
ہے اور بتدریج پھر وہ تحریک ہوتی اور بڑھتی جاتی ہے.اور وہ انسان اس میں لگ پڑتا ہے
یہاں تک کہ اس کے ملائکہ اور شیاطین میں جنگ ہو پڑتی اور ملائکہ جیت جاتے اور پھر وہ شخص
فرشتوں سے مصافحہ کر لیتا ہے.اس کے متعلق قرآن کریم میں فرمایا.إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا
اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَئِكَةُ...الآية
558
Page 567
پس ایسے لوگوں پر پھر ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور خدا کہتا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں.مت غم کھاؤ.پس اس طرح ملائکہ کا ماننا بھی نیکی سکھلاتا اور بدی سے روکتا ہے.( الحکم 24 جنوری 1905ء صفحہ 11)
وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي
بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنه وَلى عيمٌ وَمَا يُلَقَهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا
وَمَا يُلَقْهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ
( حم السجده : 36-35)
نیکی و بدی.دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہم پلہ اور خوبی میں مساوی نہیں.بدی کا
دفعیہ نیکی کے ساتھ کر دکھاؤ.اگر ایسا ہی حسن سلوک اپنے دشمنوں سے کر دکھاؤ گے تو تمہارے
دشمن بھی تمہارے بچے دوستوں اور گرم جوش والے خیر خواہوں کی طرح ہو جاویں گے.اس
نصیحت کو وہی لوگ مانیں جو بڑی بردباری اور بلند حوصلگی کا حصہ رکھتے ہیں.تصدیق براہین احمدیہ صفحہ 274، 275)
وَلَا تَسْتَوِىی.اس سوال کا جواب کہ ہمیں یہ کیونکر معلوم ہو یہ نیک ہے یا بد؟ اللہ تعالیٰ نے
فرمایا کہ نیکی اور بدی کی حقیقت پر غور کرنے سے خود بخود یہ بات معلوم ہو جاتی ہے.بہ لحاظ اثرات و
نتائج بھی یہ دونوں چیزیں الگ ہیں.نبی کریم صلعم نے بھی ایک اصول بتایا ہے دَعْ مَا يُرِيبُكَ إِلى
مَا لَا يُريبُك.جو چیز تجھے دل میں کھٹکتی ہے اسے چھوڑ دے اور اختیار کر اسے جو نہ کھٹکے.ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ - بعض اوقات فوری جوش میں امتیاز نہیں ہو سکتا.اس لئے ایک
عمدہ طریق بتایا ہے کہ صبر سے کام لیا جائے.جوش کے رفع ہونے پر اصل کیفیت کھل جاتی
ہے - يُلَقَهَا تَلْقِي بِالْقُبُول کے معنی ہیں.خوشی سے کسی بات کو مان لینا.صبر کہتے ہیں اس مصیبت کو برداشت کر لینے کو جو کسی فعل یا ترک فعل سے حکم الہی کے
ماتحت پیش آوے.ذُو حظ عظیم اللہ تعالی ساری دنیا کو متاع قلیل فرماتا ہے.پس
559
Page 568
اندازہ کرو کہ عظیم کتنا بڑا ہوگا.ضمیمه اخبار بدر قادیان 2 مارچ 1911ء)
وإما تلا ذلك من الشَّيْطي ترغ فَاسْتَعِل بالله.إنه هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.(حم السجدة: 37)
فَاسْتَعِذْ بِاللہ.یہ غیظ و غضب کے روکنے کا طریق سکھایا کہ دُعا کرلو اور خدا سے مدد و
پناہ مانگو.(ماخوذ از حقائق الفرقان )
ضمیمه اخبار بدر قادیان 2 مارچ 1911ء)
حضرت خلیفہ امسح الثالث رحمہ اللہ نے سور پٹخم السجدۃ کی آیات 31 تا33 کی تلاوت
اور ترجمہ کے بعد فرمایا:
اگر چہ ان آیات میں جو میں نے ابھی تلاوت کی ہیں عید کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا تاہم
حقیقی عید کی تمام مسرتیں اس میں جمع کر دی گئی ہیں.ایک مومن کی حقیقی عید یہی ہوتی ہے کہ
اسے خدا کا پیارمل جائے.اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر رجوع
برحمت ہونا اور انہیں فوز و فلاح کی شکل میں جنتوں کی بشارتوں سے نوازنا ہی اصل عید ہے.ادھر عید کہتے ہی بار بار آنے والی خوشی کو ہیں اسی لئے اللہ تعالیٰ نے ایک نہیں مومنوں کے لئے
کئی عید میں مقرر کی ہیں جو بار بار ظاہر ہو کر ایک مومن کو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے پیار کی
بشارتوں سے نوازنے کا موجب بنی ہیں.خطبات ناصر جلد دہم صفحہ 83، 84)
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر قوم اور ہر جماعت نے اپنے لئے خوشیوں
کے تہوار بنائے ہوئے ہیں اور ہماری عید کا دن تو یہ ہے جو رمضان کی عبادت کے بعد آتا ہے
اسی طرح ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا کہ مدینہ میں مدینہ کے دونوں بڑے قبائل مختلف
موقعوں کی یاد میں تہوار مناتے ہیں ان سے بہتر اے مسلمانو! اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے انتظام
560
Page 569
کر دیا ہے ایک عید الفطر کا جس کو ہم چھوٹی عید کہتے ہیں اور ایک عید الاضحیہ کا.(سنن ابی داود کتاب الصلوة )
انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ وقفہ وقفہ کے بعد خوشی منائے اور یہ فطرت میں اس لئے رکھا گیا
ہے کہ ایک خاص زمانہ اور وقت میں انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت میں انہماک کے بعد ایک وقتی
انعام پائے اور اس انعام کی خوشی میں وہ اپنی مسرت کا اظہار کرے.فطرت کے اندر جو خوشی منانے
کا جذبہ ہے وہ مٹ نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ فطرت کا ایک حصہ ہے لیکن اس جذبہ کے اظہار کے خدا
کے بتائے ہوئے جو مواقع تھے وہ انسان ہمیشہ ہی بھولتا رہا ہے.ہر نبی نے اپنی امت پر بعض
ذمہ داریاں ڈالیں اور پھر ان کے لئے عید اور خوشی کے سامان بھی پیدا کئے وہ خوشی تو مناتے رہے
اور آج تک منارہے ہیں لیکن جو ذمہ داریاں ان پر عائد کی گئی تھیں ان
کو وہ بھلا بیٹھے اور جس وجہ سے
خوشی منائی تھی وہ وجہ باقی ندر ہی.ایک ظاہری چھلکا باقی رہ گیا اور روح مرگئی.انسانی فطرت میں خوشی منانے کا یہ جذبہ اتنا راسخ ہے کہ میں نے اپنی طالب علمی کے زمانہ
میں یہاں بھی اور انگلستان میں بھی یہ دیکھا ہے کہ بعض دفعہ خوشی حاصل کرنے کے اس جذ بہ کو
سیر کرنے کے لئے طالب علم کہتے تھے کہ آؤ ہنسیں اور پھر وہ کسی وجہ کے بغیر قہقہے لگانے
شروع کر دیتے.کوئی وجہ نہیں ہوتی تھی اور وہ قہقہے لگارہے ہوتے تھے.وہ ایک دوسرے کو
کہتے آؤ ہنسیں اور پھر وہ بلا وجہ ہنسنے لگ جاتے تھے.غرض دنیا میں اس قسم کی بہت ساری
عیدیں ہیں کہ قہقہہ تو لگ رہا ہے لیکن وہ قہقہہ کس وجہ سے اور کیوں ہے اس قہقہہ لگانے
والے کو بھی علم نہیں ہوتا.چہرہ پر تو مسکراہٹ ہے لیکن دل میں خوشحالی کے جذبات نہیں.وہ
ا
کیفیت نہیں.حقیقی خوشی وہی ہے جس کے منانے کا اللہ حکم دے اور جس کی کیفیت پیدا کرنے کا اللہ تعالیٰ
سامان پیدا کر دے.جو آیت کریمہ میں نے ابھی تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا
ہے کہ خوش ہو اور خوشیوں سے اپنے وجود کو بھر لو.عید مناقَ - وَابْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ
تُوعَدُونَ کیونکہ جس خوشی اور جس جنت کا تمہیں وعدہ دیا گیا تھا وہ تمہارے لئے میسر آ گئی ہے
561
Page 570
یا تمہارے پہلے کی نسبت زیادہ قریب ہو گئی ہے اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ انسان کے لئے
جنت پیدا کرتا ہے اور حقیقتاً اس دنیا کی جنت کو ہی ہم ایک عظیم جسمانی اور روحانی انقلاب کے
بعد اپنے ساتھ برزخ کی دنیا میں لے کے جاتے ہیں.لیکن عام طور پر وہ جنت آنکھوں سے
اوجھل رہتی ہے لیکن اس جنت کی وجہ سے جو خوشی پیدا کی جاتی ہے اسے بچہ بھی اپنی عمر کے لحاظ
سے محسوس کرتا ہے اسے پاگل بھی اپنی عقل کے مطابق مناتا ہے پس اللہ تعالیٰ نے یہاں اس
آیت میں ہمیں حکم دیا ہے کہ اپنے آپ کو خوشیوں سے بھر لو اور عید مناؤ.اس لئے کہ دو قسم کی عید
کے سامان آج تمہارے لئے پیدا کئے گئے ہیں ایک معرفت الہی کا سامان جیسے فرمایا ان
الَّذِينَ قَالُوا ربنا الله اس میں عرفان الہی کے سامان کی طرف اشارہ ہے کہ وہ لوگ جو
علی وجہ البصیرت اعلان کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے رب کی معرفت اپنی استعداد کے مطابق
حاصل کی اور ہم دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم سب کا رب وہ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا جس
نے ہمارے جسموں کو اور ہماری روحوں کو اور جس نے ہمارے جسم کے مختلف خواص اور ہماری
روح کی مختلف صفات کو پیدا کیا اور جو ان صفات اور ان خواص کو پیدا کرنے کے بعد ان خواص
اور ان صفات کو ان کے دائرہ استعداد میں اور ان کی نشوونما کو کمال تک پہنچانے کا متکفل ہوا
اور ذمہ وار بنا.وہی ہمارا رب ہے اس کے علاوہ ہمارا کوئی اور رب ہو ہی نہیں سکتا.عقلاً بھی
نہیں ہوسکتا اور پھر فطرت انسانی بھی اس کو دھتکارتی ہے اور جو وحی آسمانی اللہ تعالیٰ نے نازل
کی اس سے تو ہمارے سامنے یہ چیزیں بڑی وضاحت کے ساتھ آجاتی ہیں کہ ربنا اللہ اللہ ہی
ہمارا رب ہے اور وہ ہستی جو تمام صفات حسنہ سے متصف ہے اور جس کے اندر کوئی عیب نہیں
پایا جا تا ہی ربوبیت کا سزاوار ہے اور اہل اور مستحق ہے اور اسی کو رب سمجھنا چاہئے اور رب اپنے
وجود میں محسوس کرنا چاہئے.اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کی پہچان خوشی کے سامانوں کا ایک ذریعہ بنتا ہے کیونکہ یہ ایک
ابتدائی اور بنیادی چیز ہے بلکہ یوں کہا جاسکتا ہے کہ سب سے بڑا سامان ہماری خوشیوں کا یہی
562
Page 571
ہے کہ اپنے اس رب کو پہچانے لگیں اور اس کا عرفان رکھنے لگیں جو رب بھی ہے اور دیگر بہت
سی صفات حسنہ سے متصف ہے اور جب اس کا حسن ہم پر جلوہ گر ہوتا ہے تو ہمارے ذہن دنیا کی
ساری خوبصورتیوں کو بھول جاتے ہیں اور جب ہم اس کے احسان کو پہچاننے لگتے ہیں تو ہم اس
حقیقت کو پاتے ہیں کہ وہی ایک محسن حقیقی اور معطی حقیقی ہے اور جتنے دوسرے وجود بظاہر ایسے
معلوم ہوتے ہیں کہ وہ دوسروں پر احسان کر رہے ہیں وہ بھی اسی کی توفیق ، اسی کے منشاء اور حکم
سے احسان کی طاقت اور قوت پاتے ہیں ورنہ خود ان کے اپنے وجود میں کوئی بھی ایسا نہیں اور
قابلیت نہیں اور ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جو انہوں نے اپنے زور سے اور اپنی طاقت
سے حاصل کی ہو جس ہنر اور قابلیت کے نتیجہ میں وہ احسان کا ارادہ کریں اور جس چیز کو لے کر وہ
دوسرے پر احسان کریں اور اسی کو عطا کریں.غرض نہ وہ چیز جو ان کے پاس ہے ان کی اپنی یا
ان کے اپنے زور سے حاصل کردہ ہے اور نہ ان کی احسان کی قوت اور ارادہ اور خواہش اپنی
ہے.یہ سب کچھ ربنا اللہ اللہ کی توفیق سے ہی میسر آتا ہے جو ہمارا رب ہے.کئی لوگ
دوسروں کو عطا کرتے ہیں اور صفات باری سے عملی طور پر متصف ہونے کی کوشش کرتے
ہیں اور اس کے قرب کو پاتے اور اس کو پہچانتے اور اس کا عرفان حاصل کرتے ہیں اور ان
کے لئے عید کے دن اور عید کے اوقات مقرر کئے جاتے ہیں..دوسرا بڑا ذریعہ یا سامان جس کے نتیجہ میں انسان کے لئے حقیقی عید یا خوشی پیدا ہوتی ہے وہ
استقامت ہے.جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا
استقامت کے معنی یہ ہیں کہ وقتی طور پر اور عارضی طور پر اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی دینے کا سوال
نہیں بلکہ جب اپنے رب کو اور اپنے اللہ کو پہچان لیا تو اس کی کامل اطاعت اور مسلسل اطاعت
اور ہمیشہ کی اطاعت اور ہمیشہ کا پختہ تعلق اس سے ضروری ہے کیونکہ جو آج کھاتا ہے اور کل بھوکا
رہتا ہے اس کو سیر نہیں کہا جاسکتا.رمضان میں ہم نے یہ سبق بھی سیکھا ہے ہم دن کو بھوکا ر ہتے
تھے اور رات کو ہم کھاتے تھے اور جتنا چاہتے تھے کھاتے تھے اور دن کو ہم بھو کے رہتے تھے تو
563
Page 572
ہم بڑی بھوک محسوس کرتے تھے.پس رات کا کھانا دن کی سیری کا سبب نہیں بنا کرتا.اسی
طرح اللہ تعالیٰ سے ایک وقت میں تعلق کو قائم کر کے اس کے پیار کو وقتی طور پر حاصل کرلینا.اس دنیا میں آئندہ زمانہ کی سیری کے سامان نہیں پیدا کیا کرتا.اُس دنیا کے حالات تو تفصیلاً ہم
جانتے نہیں اس لئے ہم اس دنیا کی بات کریں گے.جس طرح اس دنیا میں کھانے کی بار بار
ضرورت پڑتی ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کے پیار کی نگاہوں کی ہمیں بار بار ضرورت پڑتی ہے اور
وہ پیار کی نگاہیں قربانی اور ایثار کے بغیر ہم حاصل نہیں کر سکتے.غرض استقامت کے معنی ہیں
کہ جب تعلق قائم کر لیا تو پھر وہ ٹوٹے گا نہیں اور وہ اتنا پختہ ہے کہ دنیا جتنا چاہیے زور لگا لے وہ
ٹوٹ نہیں سکتا.لیکن اللہ تعالیٰ دنیا کو یہ بتانے کے لئے کہ یہ لوگ میرے بڑے ہی محبوب اور
پیارے بندے ہیں.یہ مجھ سے چمٹ گئے ہیں اور اب تم ان کو میرے دامن سے علیحدہ نہیں
کر سکتے.نیز دنیا کو دکھانے کے لئے اور ان کو سبق دینے کے لئے کہ میں اپنے بندوں پر
بلائیں بھی نازل کرتا ہوں انہیں بلاؤں میں ڈالتا ہے.وہ خاموشی بھی اختیار کرتا ہے اور ماں کی
طرح کبھی یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ جاؤ میں تم سے ناراض ہوں اور اس ناراضگی کے آثار کے پیچھے
مسکراہٹیں جھلک رہی ہوتی ہیں.دیکھنے والی آنکھ وہ دیکھتی ہے لیکن
دنیا یہ سمجھتی ہے کہ خدا اس
سے کلام کرتا تھا لیکن آج وہ اس کو بھول گیا.اللہ تعالیٰ اس پر رحمت اور پیار کی نگاہ رکھتا تھا
لیکن آج ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس نے اس سے اپنا منہ پھیر لیا لیکن اس نے اس سے منہ اس
لئے نہیں پھیرا کہ وہ اس سے ناراض تھا.اس نے اس سے منہ اس لئے نہیں پھیرا کہ اس کو
اور دنیا کو اس امتحان اور غصہ کے پیچھے اور ان آفات کے ماورا خدا کا پیار اور رضا نظر نہ آئے وہ
اپنا غصہ بھی دکھاتا ہے اور انسان کو آزماتا بھی ہے اور اس سے وہ دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ میرا
حسن اور احسان اور میری محبت اور میری رضا ایسی زبر دست تاثیر رکھنے والی ہے کہ جب وہ کسی
انسان کو مل جاتی ہے تو وہ اس کے بعد مجھ سے پرے نہیں ہوتا.دنیا جو چاہے کرے وہ اس کو
میرے دامن سے چھڑانے میں کامیاب نہیں ہو سکتی.یہ ہے استقامت.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
564
Page 573
رمضان آیا.تم نے روزے رکھے رمضان آیا تم نے خلوص نیت کے ساتھ راتوں کو اٹھ کر میری
تسبیح اور میری تحمید کی اور میرے ذکر میں تم مشغول رہے.رمضان آیا.تم نے نفس کی خواہشات
کو میری خاطر رو کے رکھا اور ان کو اپنا غلام بنایا تم اپنے نفس کی ان خواہشات کے خود غلام نہ
بنے.رمضان
آیا اور تم نے میری چلائی ہوئی اندھیریوں کی طرح اپنے اموال کو مستحقین میں لٹایا
اور سب دے دلا کر تم نے محسوس کیا کہ یہ خدا کا تھا.خدا کی رضا کے لئے ہم نے یہ چیز اس کو
دی اور یہ گھاٹے کا سودا نہیں بلکہ بڑے نفع کا سودا ہے کہ ہم نے جو دیا وہ بھی اس سے لے کر ہم
نے دیا ہے یہ ایسی بات ہے کہ آپ کسی دکاندار کے پاس جائیں اور وہ عید منانے کے لئے
پانچ سوروپیہ کا کپڑا آپ کو دے اور جب آپ کپڑا پھڑ وا چکیں تو وہ چپ کر کے آپ کی جیب
میں پانچ سوروپیہ ڈال دے اور آپ اسی کی رقم اسے دے کر وہ کپڑا لے آئیں اور یہ سراسر فائندہ کا
سودا ہے گھاٹے کا تو یہاں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا.شاید الفاظ اسے ٹھیک طور پر بیان نہ کرسکیں
لیکن اس سے بھی بڑھ کر ستا سودا ہمارا ہمارے رب کے ساتھ ہے کہ نہ صرف ہم نے جو اس
کے حضور پیش کیا وہ بھی اس کی عطا تھی بلکہ پیش کرنے کی طاقت اور یہ جذبہ جو ہمارے دل میں
پیدا ہوا کہ ہم اس کی محبت اور رضا کو حاصل کریں یہ بھی اس کی توفیق سے ہوا.ہم نے اس کی راہ
میں اپنے اموال کو خرچ کیا ہم دعاؤں میں لگے رہے اور جب رمضان ختم ہوا تو خدا نے ہمیں کہا
تم خوش ہو اور خوشی سے اچھلو اور خوشی سے اپنے وجود کو بھرلو کہ تم ایک درجہ میں کامیاب ہو گئے.تمہارے پہلے گناہ معاف کر دئے گئے ہیں اور نئی زندگی کا ایک زمانہ اور ایک دور تم پر آرہا ہے
تم اس سے زیادہ رحمتوں کو حاصل کرنے کی آنے والے سال میں کوشش کرنا و آبشرُوا
بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ تمہیں دنیا میں بھی ایک جنت کا وعدہ دیا گیا تھا وہ جنت تمہیں مل
رہی ہے تمہیں استقامت، صبر اور ثبات قدم دکھانا پڑے گا تا کہ ساری زندگی یہ جنت تمہارے
ساتھ رہے اگر تم کسی وقت خدا کی معرفت کے حصول کے اور شیطانی وسوسوں کے نتیجہ میں خدا کی
بجائے شیطان کی طرف مائل ہو جاؤ یا کچھ خدا کو پہچانو اور کچھ شیطان کو پہچانو تم کچھ اللہ کی قدر
565
Page 574
کرو اور کچھ اس کی قدر کرو جس کی اللہ کی نگاہ میں کوئی قدر ہی نہیں تو پھر تم سے جنت واپس لے
لی جائے گی لیکن بہر حال خدا کہتا ہے کہ میں رمضان کی مخلصانہ دعاؤں کو قبول کرتا ہوں اور
تمہارے لئے خوشیوں کے سامان پیدا کرتا ہوں.یہ عید ہے جس کے منانے کے لئے ہم آج
جمع ہوئے ہیں خدا کرے کہ ہماری نہایت ہی حقیر قربانیاں ہماری اس استقامت کی کوشش
کے نتیجہ میں قبول ہو جائیں جو ہم نے کی.استقامت بڑا ہی اہم اور بڑا ہی مشکل کام ہے.اس
کے بغیر گزارہ بھی نہیں لیکن یہ معمولی کام بھی نہیں.حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے
بہت جگہ اس کے متعلق بیان فرمایا ہے.میں اس کی اہمیت کو بیان کرنے کے لئے ایک
مختصر سا اقتباس اپنے بھائیوں کے سامنے اس وقت پیش کر دیتا ہوں.آپ فرماتے ہیں.کمال استقامت یہ ہے کہ چاروں طرف بلاؤں کو محیط دیکھیں کہ خدا کی راہ میں جان اور
عزت اور آبرو کو معرض خطر میں پاویں اور کوئی تسلی دینے والی بات موجود نہ ہو یہاں تک کہ خدا
تعالیٰ بھی امتحان کے طور پر تسلی دینے والے کشف یا خواب یا الہام کو بند کرے اور ہولناک
خوفوں میں چھوڑ دے اس وقت نامردی نہ دکھلاویں اور بزدلوں کی طرح پیچھے نہ ہٹیں اور وفاداری
کی صفت میں کوئی خلل پیدا نہ کریں.صدق اور ثبات میں کوئی رخنہ نہ ڈالیں ذلت پر خوش
ہو جائیں موت پر راضی ہو جائیں اور ثابت قدمی کے لئے کسی دوست کا انتظار نہ کریں کہ وہ
سہارا دے.نہ اس وقت خدا کی بشارتوں کے طالب ہوں کہ وقت نازک ہے اور باوجود
سراسر بیکس اور کمزور ہونے کے اور کسی تسلی کے نہ پانے کے سیدھے کھڑے ہو جائیں اور ہر چہ
بادا باد کہہ کر گردن کو آگے رکھ دیں اور قضاء و قدر کے آگے دم نہ ماریں اور ہر گز بے قراری
اور جزع فزع نہ دکھلاویں جب تک کہ آزمائش کا حق پورا ہو جائے یہی استقامت ہے جس
سے خدا ملتا ہے.یہی وہ چیز ہے جس کی رسولوں اور نبیوں اور صدیقوں اور شہیدوں کی خاک سے
اب تک خوشبو آرہی ہے.اسلامی اصول کی فلاسفی روحانی خزائن جلد 10 صفحہ 420)
خطبات ناصر جلد دہم صفحہ 31 تا 37)
566
Page 575
حضرت خلیفہ المسیح الرابع رحمہ اللہ نے خطبہ جمعہ فرمودہ 14 فروری 1983ء ء میں سورة
لحم السجدة کی آیات 31 تا 33 کی تلاوت کے بعد فرمایا:
قرآن کریم نے جہاں داعی الی اللہ کی تعریف فرمائی ہے اس سے پہلے وہ پس منظر بھی
بیان فرمایا ہے جو اس جماعت کا پس منظر ہے جس میں سے داعی الی اللہ نکلتے ہیں اور ان حالات
پر بھی روشنی ڈالی ہے جن حالات کے باوجود یا جن حالات کے نتیجے میں داعی الی اللہ پیدا ہوتے
رہتے ہیں.چنانچہ جو آیات میں نے ابھی تلاوت کی ہیں ان میں اسی مضمون
کو تفصیل سے بیان فرمایا گیا
ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ وہ داعی الی اللہ کون ہیں اور کن لوگوں میں سے نکلتے ہیں.چنانچہ ان
کے متعلق فرمايا إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یہ اعلان
کرتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس دعویٰ پر استقامت اختیار کرتے ہیں.جہاں تک ربنا اللہ کے دعویٰ کا تعلق ہے اس کے ساتھ بظاہر تو استقامت کی کوئی بات نظر
نہیں آتی کہ کیوں اس دعویٰ کی وجہ سے استقامت اختیار کرنے کی ضرورت پیش آئے.اس
لئے کہ سب لوگوں کا رب اللہ ہے اور فی ذاتہ محض یہ دعوی کرنا کہ اللہ ہمارا رب ہے بظاہر
دشمنیوں کو انگیخت نہیں کرتا اور کوئی عقلی وجہ سمجھ میں نہیں آتی کہ اس دعویٰ کے نتیجے میں دنیا ایسے
لوگوں پر کیوں مصیبتیں برپا کرے گی جن کی وجہ سے استقامت کا سوال پیدا ہوگا.لیکن معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو ربنا اللہ کہتے ہیں ان کا انداز عام دنیا کے ربنا اللہ کہنے
والوں سے مختلف ہوتا ہے.ان کے اندر زیادہ سنجیدگی پائی جاتی ہے، ان کے اندر زیادہ خلوص پایا
جاتا ہے اور ربنا اللہ کا دعویٰ ان کے اعمال میں ایسی تبدیلیاں پیدا کر دیتا ہے کہ یہ لوگ عام دنیا
کے لوگوں سے کچھ مختلف شکلیں اختیار کر جاتے ہیں.ربنا الله کا معنی ہے، اللہ ہمارا رب ہے.وہی ہے جس نے پیدا کیا، وہی ہے جو پرورش
کرتا ہے، وہی ہے جو تربیت دے کر آگے بڑھاتا ہے.مربی بھی ہمارا وہی ہے اور پالن ہار بھی
وہی.اسی سے ہم دنیا کے رزق حاصل کرتے ہیں اور اسی سے روحانی رزق حاصل کرتے ہیں.567
Page 576
یعنی جسمانی اور روحانی ، دونوں غذا ئیں ہمیں اپنے رب سے ملتی ہیں اور وہ ہمیں کافی ہے.اس
کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی اور رب کی ضرورت نہیں.اگر آپ اس دعویٰ پر غور کریں تو آپ کو
معلوم ہو جائے گا کہ ایک طرف تو یہ دعویٰ کلیہ اللہ پر انحصار کر دیتا ہے اور دوسری طرف کلیۃ
غیر اللہ سے مستغنی بھی کر دیتا ہے.ربنا اللہ کا دعویٰ کرنے والوں پر کئی قسم کے ابتلا آتے ہیں جن کے نتیجے میں انہیں استقامت
دکھانی پڑتی ہے.کچھ تو اندرونی ابتلا ہیں اور کچھ بیرونی ابتلا.اندرونی طور پر تو یہ قوم تربیت کے
ایسے مشکل رستوں سے گزرتی ہے کہ قدم قدم پر ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ جس رب کے پیچھے تم
چل رہے ہو اس کے نتیجے میں تو تمہارا رزق کم کیا جائے گا اور تم مشکلات اور مصیبتوں میں مبتلا
کئے جاؤ گے.تم عجیب پاگل قوم ہو کہ بڑی محنت کے ساتھ اپنی حکمتوں کو استعمال کرتے ہوئے
اور اپنی جسمانی طاقتوں کا استعمال کرتے ہوئے تم روپیہ کماتے ہو اور پھر اس روپے کو از خود خدا
کے نام پر خرچ کر دیتے ہو اور دعویٰ یہ ہے کہ ربنا الله، اللہ ہمارا رب ہے.اچھا اللہ تمہارا رب
بنا کہ پہلے حال سے بھی بدتر ہو گئے.دنیا کمانے والے جو تمہارے بھائی بند ہیں وہ تو کمانے کے
رستے بھی زیادہ رکھتے ہیں اور خرچ بھی خالصتاً اپنی ذات پر کرتے ہیں.ان کا رزق زیادہ
بابرکت ہے یا تمہارا جن کی آمد کے رستے تنگ ہیں اور خرچ کے رستے زائد ہو گئے اور تم ایسی
جگہ بھی خرچ کرنے لگے جس کے نتیجے میں تمہیں کوئی ذاتی فائدہ نہیں پہنچتا.اب دیکھیں کتنا بڑا ابتلا ہے کہ ربنا اللہ کہنے والوں نے جھوٹ کی کمائی کے رستے اپنے
اوپر بند کردئیے.ربنا اللہ کہنے والوں نے رشوت کی کمائی کے رستے بند کردئیے.ربنا الله کہنے والوں نے ظلم کے ذریعے ہتھیائی ہوئی جائیداد میں حاصل کرنے کے رستے اپنے
او پر بند کر دئیے.ربنا اللہ کہنے والوں نے تکڑی کے تول میں خرابی کے ذریعے زیادہ آمدن پیدا
کرنے کے رستے بند کر دئیے.ربنا اللہ کہنے والوں نے چوری کے رستے بند کئے، ڈاکے کے
رستے بند کئے اور دھو کے کے رستے بند کئے.باقی دنیا کے لئے رزق کے کتنے ہی رستے کشادہ
568
Page 577
ہیں اور کتنی ہی ان گنت را ہیں ہیں جو دنیا والوں کے لئے کھلی ہیں مگر ربنا اللہ کہنے والوں نے ان
سب راہوں سے منہ موڑ لیا اور پھر خرچ کی راہوں میں اپنے لئے ایسی راہیں تجویز کیں کہ وہ
پاکیزہ رزق جو بظاہر تنگ رستوں سے انہیں حاصل ہوتا ہے اور دنیا کے مقابل پر ان کی آمد کے
وسائل بہت محدود نظر آتے ہیں، اپنی اس قلیل آمد کو بھی وہ خدا کی راہ میں خرچ کرنے لگ گئے
اور دعویٰ یہ ہے کہ ربنا الله اللہ ہمارا رازق ہے.یہ وہ اندرونی آزمائش ہے جس میں سے یہ لوگ گزرا کرتے ہیں اور اسی کا نام استقامت
ہے کہ اپنے دعوی کو سچا ثابت کر کے دکھاتے ہیں اور ہر قسم کے مصائب کو ان کی آنکھوں میں
آنکھیں ڈال کر دیکھتے ہیں اور کسی قسم کا خوف نہیں کھاتے اور یقین رکھتے ہیں کہ وہی رازق ہے
اور اسی سے ساری برکتیں حاصل ہوتی ہیں اور اسی کے نام پر خرچ کرنے میں دراصل رزق کی
برکتوں کی چابی رکھی گئی ہے.اس یقین کے ساتھ وہ استقامت اختیار کرتے ہیں.پھر ایک بیرونی ابتلا ان پر آتا ہے.باہر کی دنیا کہتی ہے کہ اچھا اگر تم اللہ کو ہی رب سمجھ
رہے ہو اور سمجھتے ہو کہ وہی تمہارے رزق کا انتظام کرتا ہے اور وہی تمہیں بچاتا ہے تو تمہاری
اندرونی قربانی کافی نہیں، ہم بھی کچھ حصہ ڈالیں گے.یعنی کچھ تمہاری دوکانیں ہم لوٹیں گے،
کچھ تمہاری جائیداد میں ہم برباد کریں گے، کچھ جائز ورثوں سے تمہیں ہم محروم کر دیں گے، کچھ
جائز ترقیات سے تمہیں ہم عاری کر دیں گے اور ان کے رستے میں روکیں کھڑی کر دیں گے،
کچھ حصول تعلیم کے حق تم سے چھین لیں گے اور وہ تعلیم جو تمہارے رزق کا ذریعہ ہے ، ہم
حتی المقدور کوشش کریں گے کہ تم اس تعلیم میں قدم آگے نہ بڑھا سکو.غرض یہ کہ ہر قسم کی
مشکلات جو رزق کے حصول کے رستے میں حائل کی جاسکتی ہیں وہ تمہاری راہ میں حائل کریں
گے پھر دیکھیں گے کہ تم کس شان کے ساتھ اور کس یقین کے ساتھ ربنا اللہ کہتے ہو.یہ
استقامت کا دوسرا دور شروع ہو جاتا ہے.استقامت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز ایسی حالت میں بھی کھڑی رہے کہ جب اس کے
569
Page 578
کھڑے رہنے کی راہ میں روکیں ہوں اور اس کو ہر طرف سے دھکے پڑ رہے ہوں.ویسے تو کوئی
چیز کھڑی ہو تو اس کے لئے قام کا لفظ بولتے ہیں.درخت کھڑے ہیں ان کی اس حالت کے
متعلق بھی قامہ کا لفظ استعمال کریں گے.انسان کھڑا ہو تو وہ بھی قائد کی حالت میں ہوتا ہے
لیکن شدید آندھی میں بھی جو درخت قائم رہ جائے اس کے متعلق استقام کا لفظ استعمال کریں
گے.اسی طرح شدید زلازل میں بھی کوئی عمارت نہایت شان کے ساتھ سر بلند کھڑی رہے اور
سرنگوں نہ ہو، اس کے متعلق بھی استقام کا لفظ بولیں گے.اسی طرح شدید مشکلات اور
مصائب میں کوئی انسان اپنے موقف پر قائم رہے اور ایک انچ بھی اس سے انحراف نہ کرے
اس کے متعلق بھی انتقام کا لفظ ہی استعمال کریں گے.اللہ تعالی کی طرف سے ہر قسم کے ابتلا ان لوگوں پر عائد کئے جاتے ہیں جو ربنا اللہ کا دعویٰ
کرتے ہیں.تقدیر خداوندی کی طرف سے ان کے امتحانات لئے جاتے ہیں.ان پر ایسے
اندرونی اور بیرونی ابتلا آتے ہیں جو حد کر دیتے ہیں.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثُمَّ اسْتَقَامُوا کہ کوئی
مصیبت، کوئی زلزلہ، کوئی قیامت ان کے پائے ثبات میں لغزش نہیں پیدا کر سکتی ، کوئی چیز ان
کو اس راہ سے ہٹا نہیں سکتی جس پر یہ گامزن ہوتے ہیں اور اسی لیے ان کی راہ کا نام بھی مستقیم
رکھا گیا اور مستقیم راہ پر قائم رہنے کے لئے یہ دعا سکھائی گئی اهْدِنَا القِيرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ
إيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کے بعد اهْدِنَا القِرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کی دعا یہ بتارہی ہے
کہ ربنا اللہ یعنی اللہ کی عبادت کرنا اور کسی اور کی طرف منہ نہ کرنا ، اس دعویٰ کے نتیجے میں لازماً
مشکلات پیدا ہوں گی اور اگر دعائیں نہیں کرو گے تو ان مشکلات میں ثابت قدم نہیں رہ سکو گے.پس
صراط مستقیم در اصل استقامت کی تشریح ہے یا استقامت صراط مستقیم کی تشریح ہے.یہ دونوں ایک
دوسرے پر روشنی ڈال رہے ہیں.پس فرمایا کہ جب وہ استقامت اختیار کرتے ہیں تو ہم انہیں
اس سے پہلے استقامت کا گر سکھا چکے ہوتے ہیں.وہ اپنے زور بازو سے مستقیم نہیں رہ سکتے بلکہ ہم انہیں
دعائیں سکھاتے ہیں.وہ گریہ وزاری کے ساتھ ہماری طرف جھکتے ہیں اور اهْدِنَا القِرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کی
570
Page 579
دعا جاری رہتی ہے.اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ انہیں استقامت عطا فرماتا ہے.پھر جب وہ استقامت دکھاتے ہیں تو ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے؟ فرمایاتتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ
الْمَلائِكَةُ أَلا تخافُوا وَلَا تَحْزَنُوا یعنی بکثرت ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہوئے نازل
ہوتے ہیں أَلا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا کہ کوئی خوف نہ کرو، کوئی غم نہ کھاؤ.لیکن یہ عجیب بات ہے
کہ استقامت دکھانے والے لوگوں کو یہ فرشتے کہتے ہیں کہ کوئی غم نہ کھاؤ اور کوئی خوف نہ کرو
حالانکہ غم کی وجوہات بھی نظر آتی ہیں اور خوف کی وجوہات بھی نظر آتی ہیں.پھر اس پیغام کا کیا
مطلب ہے کہ کوئی غم نہ کھاؤ اور کوئی خوف نہ کرو؟ کیونکہ استقامت خود ایسے حالات کی متقاضی
ہوتی ہے جن کے نتیجے میں غم بھی پیدا ہوگا اور خوف بھی پیدا ہو گا.مثلاً اگر کسی ایسے انسان کو جسے
نقصان پہنچا ہو آپ کہہ دیں کہ غم نہ کرو تو اس سے اس کا غم کس طرح دُور ہو گا؟ یا اگر خوف کے
مقام پر آپ یہ اعلان کر دیں کہ خوف نہ کرو تو اس سے خوف کس طرح زائل ہوسکتا ہے؟ اس
لئے دیکھنا یہ ہے کہ وہ فرشتے ایسی باتیں کر کے ان کے زخموں پر نمک پاشی کر رہے ہوتے ہیں
یا یہ پیغام کوئی اور معنی رکھتا ہے؟ لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس مضمون میں داخل ہوں، ہم
استقامت کی طرف واپس لوٹتے ہیں.استقامت کے سلسلے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے
غلاموں اور ساتھیوں نے جو عظیم الشان نمونے دکھائے ، تاریخ اسلام ان واقعات سے روشن
ہے اور ہمیشہ روشن رہے گی.وہ واقعات ایسی روشنائی سے لکھے گئے ہیں کہ جن کی چمک کبھی
ماند نہیں پڑ سکتی...اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی عظیم احسان ہے کہ اس نے جماعت احمد یہ کو بھی ان
درخشندہ مثالوں کی پیروی کی توفیق بخشی اور بخشتا چلا جا رہا ہے.تاریخ احمدیت اس دور سے گزررہی ہے اور بن رہی ہے اور بنتی رہے گی اور انشاء اللہ تعالیٰ
احمدی کبھی بھی اپنے ایمان کی صداقت پر حرف نہیں آنے دیں گے.ان کی آواز ہمیشہ یہی
رہے گی اور صرف صاحبزادہ عبد اللطیف صاحب شہید کی آواز نہیں ہوگی بلکہ ہزاروں ، لاکھوں،
571
Page 580
کروڑوں آوازیں بن کے وہ آواز گونجتی رہے گی کہ یہ زندگی کیا چیز ہے، یہ اموال کیا چیز ہیں
اور ان اولادوں کی کیا قیمت ہے؟ تم نے جو کرنا ہے کرو اور کر گزرو.ہم اپنے ایمان پر ثابت
قدم رہیں گے.یہ ہیں وہ لوگ جن کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثُمَّ اسْتَقَامُوا انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ
اللہ ہمارا رب ہے.کتنا پیارا دعویٰ ہے ، کتنا پاکیزہ دعوی ہے، کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس دعویٰ
کے بعد کوئی قوم ان سے نفرت کرنے لگے، ان سے حقارت کا سلوک کرے، ان کے امول
ٹوٹے، اور ان کی جانیں لے لیکن فرماتا ہے کہ تم سے یہی سلوک ہوگا.ثُمَّ اسْتَقَامُوا پھر جولوگ
استقامت اختیار کریں گے ان کے ساتھ میرا بھی ایک سلوک ہوگا اور وہ یہ کہ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ
الْمَلَائِكَةُ کثرت کے ساتھ ان پر فرشتے نازل ہوں گے یہ کہتے ہوئے أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا کہ
تم کوئی خوف نہ کرو اور کوئی غم نہ کھاؤ ہم تمہیں اس جنت کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا تم سے وعدہ کیا گیا
ہے.نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ہم اس دنیا میں بھی تمہارے ساتھی ہیں اور
آخرت میں بھی تمہارے ساتھی رہیں گے.وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْعَنِي أَنْفُسُكُمْ اور تمہارے لئے
اس جنت میں جس کی خوشخبری لے کر ہم آتے ہیں وہ کچھ ہے جو تمہارے دل چاہتے ہیں وَلَكُمْ
فِيهَا مَا تَدَّعُونَ اور وہ کچھ ہے جس کا تم ادعا کرتے ہو، جو تمہارا مطلوب اور مقصود ہے.جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا، ان لوگوں میں کچھ شہید بھی ہوئے انہوں نے اپنی جانیں خدا
کی راہ میں دے دیں.بہت سے ہیں جن کے اموال لوٹے گئے.بہت سے ہیں جن کے بچے
ان کی آنکھوں کے سامنے قتل کئے گئے.بہت سے ہیں جن کی ساری عمر کی کمائی ان کی آنکھوں
کے سامنے جلا کر خاک کر دی گئی.پھر الا تخافوا کا کیا مطلب ہے اور وَلَا تَحْزَنُوا کے کیا معنی
ہیں؟ وہ جنت کیسی ہے جس کی خبریں فرشتے لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جنت اسی دنیا میں
شروع ہوگئی ہے؟
اس کے اور بھی معانی ہوں گے لیکن دو معانی کی طرف میں آپ کو اس وقت توجہ دلانا چاہتا
572
Page 581
ہوں.ایک معنی تو یہ ہے کہ یہ قومی خطاب ہے کیونکہ اس میں جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے اور
اس کا مطلب یہ ہے کہ قومی تقدیر اس طرح پر بنے گی کہ فرشتے نازل ہوں گے گو انفرادی طور
پر کچھ نقصان بھی پہنچیں گے لیکن بالآخر ہر نقصان کے بعد ایسے سامان پیدا کئے جائیں گے کہ وہ
مومنین جو استقامت دکھائیں گے وہ پہلے سے بہت بہتر حالت میں ہوں گے.ان کے چند
روپے لوٹے جائیں گے تو وہ لکھوکھا میں تبدیل ہو جائیں گے.ان کی چند جانیں جائیں گی تو
لکھوکھا اور لوگ ان میں شامل ہوں گے اور ان کی اولادوں میں بھی برکت دی جائے گی.یہ
ایسی قوم ہے جس کو ہمیشہ زن ہی کے راستوں پر نہیں چلنا.ان کے غم پیچھے رہتے چلے جائیں
گے اور خوشیاں ان کے آگے آگے دوڑیں گی اور ان کے تمام خوف امن میں تبدیل کر دئیے جایا
کریں گے.اور دوسرا معنی یہ ہے کہ ان استقامت دکھانے والوں میں خدا کے کچھ ایسے بندے بھی ہوں
گے جن کو خدا کے رستے کے غم غم نظر نہیں آئیں گے.جن کو جب خدا کے نام پر ڈرایا جائے گا
اور خدا کا نام لینے کے نتیجہ میں ڈرایا جائے گا تو وہ خوف سے آزادلوگ ہوں گے.چنانچہ اس
گروہ کے متعلق ایک دوسری جگہ خدا نے فرمایا:
الا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ (يونس 63)
کہ انہی لوگوں میں جن پر فرشتے نازل ہو کر یہ کہتے ہیں کہ غم نہ کھاؤ اور خوف نہ کرو کچھ ایسے
لوگ ہیں جو غم اور خوف سے پہلے سے ہی آزاد کر دئیے گئے ہیں کیونکہ یہ اولیاء اللہ ہیں.اور ان دونوں معنوں کے لحاظ سے جنت کی خوشخبری کی تعبیریں بھی الگ الگ کی گئیں.یعنی
وہ لوگ جو شہید ہوتے ہیں ان کو جب فرشتے کہتے ہیں کہ خوف نہ کھاؤ اور غم نہ کرو یا غم نہ کرو اور
خوف نہ کھاؤ تو اس کے کیا معنی ہوتے ہیں ، کیا وہ لوگ اس کو طعن سمجھتے ہیں؟ ہر گز نہیں.کیونکہ
خدا کی راہ میں جو کچھ وہ پیش کرنا چاہتے ہیں وہ ان کے دل کی تمنا ہوتی ہے اور وہ یہی چاہتے ہیں
کہ خدا کی راہ میں شہید کر دئیے جائیں.573
Page 582
چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایسے اولیاء اللہ بھی گزرے ہیں جنہوں
نے الحاج کے ساتھ دعائیں کرائیں کہ یا رسول اللہ! دعا کریں کہ ہم شہید ہو جائیں.ایک صحابی
کے متعلق آتا ہے کہ جنگ اُحد میں وہ دشمن پر بار بار اس لئے حملے کرتے تھے کہ شہادت پائیں
لیکن ہر بار سلامت واپس لوٹ آتے.یہاں تک کہ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ! میرے
لئے دعا کریں کہ میں واپس نہ آؤں بلکہ شہید ہو جاؤں اور شہید ہو گئے اور پھر واپس نہیں لوٹے.پس خدا کی راہ میں قربانیاں دینا ہی ان لوگوں کی جنتیں ہو جاتی ہیں.یہ نہیں کہ فرشتے ان
سے دھو کہ کر رہے ہوتے ہیں اور طفل تسلیاں دے رہے ہوتے ہیں.جس طرح غریب مائیں
بعض دفعہ چاہتی تو ہیں کہ بچوں کی خواہش پوری کریں لیکن نہیں کر سکتیں پھر وہ طفل تسلیاں دیتی
ہیں کہ کوئی بات نہیں ابھی چیز مل جائے گی یا پیسے مل جائیں گے یا یہ کہ ابو گھر آجائیں گے لیکن
خدا تو غریب ماں کی طرح نہیں کہ طفل تسلیاں دے.اس کے فرشتے تو خالی ہاتھ نہیں ہوا
کرتے.ہاں اللہ ان کے دلوں پر نظر ڈالتا ہے اور جانتا ہے کہ ان کے دل کی اصل تمنائیں کیا
ہیں.پس وہ فرشتے ان کے پاس یہ کہتے ہوئے آتے ہیں کہ یہی تو وہ جنت تھی جس کا تم انتظار کر
رہے تھے ہم وہ جنت لے کر آگئے ہیں وہ مسکراہٹ جوان شہداء کے چہروں پر دیکھی گئی، وہ اسی
جنت کی خوشخبری کی مسکراہٹ تھی.ان کے دل کی کیفیت کا حال دنیا والے نہیں جانتے نہیں سمجھ
سکتے ، وہ ان سے بے خبر ہیں.یہ اس دنیا کے لوگ نہیں ہیں یہ اہل بقا ہیں جو اس فانی دنیا میں بھی
بقا کی جنت پا جاتے ہیں اور ان کے دل کی کیفیت کے مطابق ان سے سلوک کیا جاتا ہے.پس
چونکہ وہ پہلے سے ہی غموں سے اور خوف سے آزاد ہوتے ہیں اس لئے ان کے متعلق یہ سوال ہی
را نہیں ہوتا کہ وہ کسی وقت بھی غم اور خوف کی حالت میں وقت گزار رہے ہوں
کیونکہ وہ اللہ
تعالیٰ کے ساتھ زندہ رہتے ہیں.چنانچہ جہاں تک قومی زندگی کا تعلق ہے ظاہر میں بھی ایک خوف امن میں بدلتا چلا جاتا
ہے.ہر حزن کے بدلے میں اتنا عطا کیا جاتا ہے کہ اس دنیا میں بھی وہ جنت نظر آنے لگتی ہے
574
Page 583
جو قر بانیوں کے بعد عطا ہوا کرتی ہے.صحابہ کرام رضوان
اللہ علیہم اجمعین کی تاریخ بھی اس پر
گواہ ہے اور ہم خدا کے عاجز بندے بھی جس دور سے گزر رہے ہیں اس میں ہم نے بھی بار با
دیکھا کہ خدا کی راہ میں اگر ایک احمدی نے چند روپے کا نقصان برداشت کیا تو اس کے نتیجے
میں اس کو سینکڑوں روپے عطا ہوئے.سینکڑوں کا نقصان ہوا تو ہزار ہا عطا ہوئے اور ہزاروں کا
نقصان برداشت کیا تو لکھوکھہا عطا ہوئے.پس جس جماعت کو خدا کی طرف سے یہ ضمانت
دی گئی ہو کہ تمہارا ہر غم خوشی میں تبدیل کر دیا جائے گا وہ خدا کی راہ میں کس طرح قدم پیچھے
ہٹا سکتی ہے، جس جماعت کی تاریخ اس بات کی گواہ ہو کہ تمہارا ہر خوف امن میں تبدیل کر دیا
جائے گاوہ کس طرح کسی خوف کو پیٹھ دکھا کر بھاگ سکتی ہے.چنانچہ یہ وہ لوگ ہیں جن میں سے داعی الی اللہ پیدا ہوتے ہیں جو مصائب کی آنکھوں میں
آنکھیں ڈال کر آگے قدم بڑھاتے ہیں.وہ جانتے ہیں کہ ماضی ان کے لئے کیا لے کر آیا تھا
لیکن یہ بھی جانتے ہیں کہ ہر ایسے ماضی کے بعد خدا کے فرشتے ان کے لئے کیا لے کر آئے
تھے.پس وہ گواہ ہوتے ہیں ان مصائب کے بھی جو ان کو پہنچتے ہیں اور گواہ ہوتے ہیں ان
جنتوں کے بھی جو مصائب کے دور کے بعد ہمیشہ ان کو عطا کی جاتی ہیں.اس حالت میں جب وہ
اللہ کی طرف بلاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے.مَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مَنْ دَعَا إِلَى اللهِ.دیکھو
دیکھو! میرے ان بندوں سے زیادہ حسین ادعا دنیا میں کس کا ہوسکتا ہے.مصائب کے سارے
ادوار سے گزرنے کے بعد پھر یہ میری طرف بلا رہے ہیں.پہلے یہ کہا تھا کہ رب ہمارا ہے.اب کہتے ہیں کہ اے دنیا والو ! تم بھی اسی رب کے ہو جاؤ.اپنے اس تجربے کے بعد وہ یہ نتیجہ
نکالتے ہیں کہ ہم تو ایسی عظیم الشان دولت کو پاچکے ہیں کہ دل پھڑک رہا ہے کہ کاش ! تمہیں بھی
دولت نصیب ہو.اس جوش اور جذبے کے ساتھ وہ خدا کے دین کی طرف لوگوں کو بلاتے
ہیں.یہی وہ لوگ ہیں جن پر ایک عرب شاعر کا یہ شعر بڑی شان کے ساتھ چسپاں ہوتا ہے.575
Page 584
وَلَا يَكْشِفُ الْغَمَّاءَ إِلَّا ابْنُ حُرَّة
يرى غَمَرَاتِ الْمَوْتِ ثُمَّ يَزُورُهَا
( جعفر بن علبة الحارثی ، دیوان الحماسہ ، صفحہ ۱۱)
یعنی وہ مصائب یا وہ جگہیں جہاں موت کے تاریک مصائب ہجوم کر رہے ہوتے ہیں اور
ان کے چہرے رات کی طرح سیاہ ہوتے ہیں ان مصائب کو کوئی ہٹا نہیں سکتا مگر آزاد ماں کا
بیٹا جو ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا ہوا ان کی طرف بڑھتا اور پھر ان میں داخل ہو جاتا ہے.وہ ہر تاریکی کو نور اور روشنی میں تبدیل کر دیتا ہے اور ہر موت کو ایک زندگی عطا کرتا ہے.پس
یہ ہیں وہ لوگ جو رتبنا اللہ کہتے ہیں اور پھر اس دعویٰ پر استقامت اختیار کرتے ہیں، جن پر خدا
کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، جن کی ہر تاریکی نور میں تبدیل کی جاتی ہے اور پھر وہ تاریکی میں
بسنے والے ہر شخص کو اسی نور کی طرف بلاتے ہیں.ان
کا ہر غم خوشی میں تبدیل کر دیا جاتا ہے پھر
وہ دنیا کی طرف بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آؤ ہم تمہارے غم بھی اٹھائیں اور انہیں خوشیوں میں
تبدیل کریں.یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کو خوف ڈراتے ہیں لیکن وہ ان خوفوں سے خوف نہیں
کھاتے بلکہ دنیا کے خوف ہٹانے کے لئے دنیا کی طرف بڑھتے ہیں.یہ ہیں وہ داعی الی اللہ جو ہمیں بنا ہوگا کیونکہ دنیا ہزار قسم کی ظلمات کا شکار ہے، ہزار خوفوں
میں مبتلا ہے، ہزار قسم کے حزن ہیں جو سینوں کو چھلنی کئے ہوئے ہیں.پس اے احمدی! آگے
بڑھ اور ان خوفوں کو دور کر، ان اندھیروں کو روشنی میں تبدیل کر دے اور ان غموں کو راحت و
اطمینان میں بدل دے کیونکہ تیرے مقدر میں یہی لکھا گیا ہے.خطبہ جمعہ حضرت خلیفتہ المسیح الرابع رحمہ اللہ فرموده 4 فروری 1983ء.خطبات طاہر جلد 2 صفحہ 63-74)
اسی طرح حضور رحمہ اللہ نے خطبہ جمعہ فرموده 11 /فروری 1983ء میں فرمایا:
میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں قرآن کریم کی اس خوشخبری کا ذکر کیا تھا کہ خدا تعالیٰ کے وہ
بندے جو اس کی راہ میں استقامت دکھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر بکثرت فرشتے نازل فرماتا
576
Page 585
ہے جو انہیں تسلی دیتے ہیں، غم نہ کرنے کی ہدایت کرتے ہیں اور خوف سے بے نیا ز ہو جانے کا
پیغام دیتے ہیں.وہ انہیں کہتے ہیں کہ ہم آئے تو ہیں لیکن تمہیں چھوڑ کر چلے جانے کے لئے
نہیں بلکہ اب ہمیشہ ہم تمہارے ساتھ رہیں گے، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا کی زندگی کے ختم ہو
جانے کے بعد بھی.میں نے مختصراً یہ بھی ذکر کیا تھا کہ یہ فرشتے مختلف صورتوں میں مختلف قسم
کے درجات کے لوگوں کے لئے مختلف قسم کی خوشخبریاں لے کر آتے ہیں.تاریخ اسلام سے ثابت ہے کہ یہ فرشتے کبھی تمثل اختیار کرتے ہیں اور ظاہری آنکھوں
سے بھی نظر آنے لگتے ہیں.کبھی یہ فرشتے خوابوں میں ظاہر ہوتے ہیں اور خوابوں کے ذریعے جو
پیغام دیتے ہیں وہ من وعن پورا ہو جاتا ہے.کبھی یہ فرشتے سکینت بن کر دلوں پر نازل ہوتے
ہیں اور ایک یقین کامل بن کر دلوں میں بیٹھ جاتے ہیں اور جو دل میں بیٹھی ہوئی بات ہوتی ہے وہ
مخالف حالات کے باوجو د لازما پوری ہو کر رہتی ہے.آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جنگ بدر میں شریک ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ
خوشخبری کے مطابق مُسَومین فرشتے آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی مدد کے لئے
آئے.آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسومین کی یہ تفسیر فرمائی کہ یہ ایسے فرشتے ہیں جو
معلوم ہو جائیں گے ان پر گویا نشان ہیں اور ان کی کچھ علامتیں ہیں.چنانچہ صحابہ رضی اللہ عنہم بیان کرتے ہیں کہ جنگ بدر میں جو فرشتے دیکھے گئے ان کے سروں
پر سیاہ پگڑیاں تھیں اور ان کی ایک یونیفارم تھی.صحابہ نے جب ان فرشتوں کو مختلف حالتوں
میں دیکھا تو اسی طرح سیاہ پگڑیاں انہوں نے پہنی ہوئی تھیں.جب روایتیں اکٹھی ہوئیں تو وہ
تعجب میں پڑ گئے.مگر جیسا کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسومین کی تفسیر فرمائی تھی
ویسا ہی مقدر تھا اور بعینہ ایسا ہوا.اسی طرح جنگ اُحد میں جو فرشتے دکھائی دیئے ان کے سروں پر
بطور نشان سرخ پگڑیاں تھیں.( الدر المنشورزیر آیت بلی ان تصبر و او تقوا..آل عمران (126)
سرخ رنگ میں کچھ غم کا پیغام بھی تھا کیونکہ جتنا دکھ صحابہ کو جنگ اُحد میں آنحضور صلی اللہ
577
Page 586
علیہ وآلہ وسلم کے زخموں کی وجہ سے پہنچا ویسا دکھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی
میں کبھی صحابہ کو نہیں پہنچا.ایک غم کے بعد دوسرے غم کی خبر ان کو ملی اور وہ غموں سے نڈھال
ہو گئے.پس اس غزوہ میں فرشتوں کی علامت کے لئے بھی ایک ایسا رنگ چنا گیا جس میں غم
اور خون اور دکھ کا پہلو شامل ہے.رض
یہ فرشتے اجتماعی طور پر بھی صحابہ کو ان کی مدد کرتے ہوئے دکھائی دیئے اور انفرادی طور پر
بھی ایسی حالت میں کہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ کیا ہورہا ہے؟ چنانچہ جب حضرت عباس قیدی بنا
کر لائے گئے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو بتایا گیا کہ حضرت عباس کو قیدی بنانے
والے ابوالیسر ہیں.ابوالٹیسر ایک چھوٹے ، دبلے پتلے اور کمزور سے آدمی تھے.( شاید ان کی
کنیت میں بھی اسی طرف اشارہ تھا کیونکہ یسر کا معنی ہے آسانی اور ابوالئیسر کا مطلب یہ ہوا کہ
یہ آسانی کا باپ ہے.ہلکا پھلکا آسان سا آدمی ہے اور ہر شخص اس سے نپٹ سکتا ہے.)
آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے تعجب سے ابوالیسر کو مخاطب کر کے فرمایا کہ
اے ابوالٹیسر ! تم تو بہت کمزور اور ہلکے پھلکے آدمی ہو اور عباس بڑے مضبوط، بڑے توانا، لحیم شحیم
اور بڑے جنگجو انسان ہیں.مجھے بتاؤ کہ تم نے انہیں کس طرح قابو کیا ؟ تو ابوالٹیسر نے عرض کی
یا رسول اللہ ! میں نے کہاں قابو کیا تھا؟ ایک بڑا مضبوط اور طاقتور آدمی آیا تھا جس نے ان کو
پکڑا ، قابو کیا اور باندھ کر میرے سپرد کر دیا.اس طرح میں ان کو لے کر آ گیا ہوں میں نے کچھ
بھی نہیں کیا.حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایاذ را اس کی نشانیاں تو بتاؤ کہ وہ کس قسم کا
آدمی تھا؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ !انہ میں نے کبھی پہلے دیکھا اور نہ بعد میں دیکھا ہاں اس
کی علامتیں یہ تھیں.تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لَقَدْ أَعَانَكَ عَلَيْهِ مَلَكَ
گریم کہ ایک ملک کریم نے تمہاری مدد کی تھی.ایک معزز فرشتہ تھا جسے خدا تعالیٰ نے
تمہاری مدد کے لئے بھیجا تھا.( الخصائص الکبری جز اول صفحہ 202- تاریخ الخمیس لطیفہ فی استماع الطبيل بدر طبل الملوک جلد اول صفحه 390)
578
Page 587
پس واقعۂ فرشتے تمثل بھی اختیار کر لیتے ہیں اور بظاہر انسان کی شکل میں نظر آتے ہیں.جیسا
کہ حضرت مریم رضی اللہ عنہا کے متعلق فرمایا:
فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا (مريم 18)
کہ فرشتے نے حضرت مریم کے لئے ایک نہایت ہی خوبصورت اور متوازن جسم والے
انسان کا روپ دھارا اور ان پر ظاہر ہوا.آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں مختلف وقتوں میں صحابہ نے بھی ایسے نظارے
دیکھے.چنانچہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم مجلس میں تشریف فرما تھے تو ایک اجنبی
مجلس میں حاضر ہوا اس نے السلام علیکم کہا اور کچھ سوالات کئے اور پھر حضور سے اجازت لے کر
رخصت ہوا.صحابہ بہت متعجب ہوئے کیونکہ وہ باہر سے آیا تھا لیکن اس کے چہرے پر تھکن کے
کوئی آثار نہیں تھے، نہ ہی کس قسم کی گرد تھی یعنی سفر کی کوئی علامتیں نہیں تھیں.نہایت صاف
ستھرے اور پاکیزہ کپڑے پہنے ہوئے تھا.آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے تعجب کو
دیکھ کر ان سے دریافت فرمایا تم جانتے ہو یہ کون تھا؟ انہوں نے عرض کی یارسول اللہ ! ہمیں تو کوئی علم
نہیں.آپ نے فرمایا یہ جبرئیل تھا جو تمہیں تعلیم دینے کی خاطر مجھ سے سوال کر رہا تھا.چنانچہ بعض
صحابہ باہر نکلے اور دور تک گلیوں میں دیکھتے رہے لیکن کسی انسان
کا کوئی نشان نہیں ملا.( صحیح بخاری کتاب الایمان باب سوال جبریل النبی علن عن الایمان والاسلام والاحسان)
رض
پس جب ایک دفعہ یہ فرشتے صحابہ پر نازل ہوئے تو پھر یہ سلسلہ جاری رہا اور انہوں نے
صحابہ کا ساتھ نہیں چھوڑا اور حضوراکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد بھی ان کی ولایت کا
رض
تعلق جاری رہا.انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی.چونکہ صحابہ بے حد منکسر المزاج تھے
اور خائف رہتے تھے کہ کہیں دوسرے لوگ ان کے اس تعلق کی اطلاع پاکر ان کے مقام کے
متعلق زیادہ حسن ظنی نہ شروع کر دیں، اس لیے صحابہ عموماً اپنی واردات کو بیان نہیں کیا کرتے
تھے.لیکن بعض ایسے اجتماعی رنگ کے واقعات بھی ہیں جن میں دوسرے کئی لوگ گواہ ہوئے
579
Page 588
اور وہ تاریخ اسلام میں محفوظ چلے آرہے ہیں.چنانچہ ایک دفعہ شمالی سرحد پر جنگ ہو رہی تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس وقت مدینہ میں
خطبہ دے رہے تھے.خطبہ کے دوران اچانک آپ نے فرمایا يَا سَارِيَةَ الْجَبَلُ يَا سَارِيَةً
الجبل.اور یہ کہہ کر پھر خطبہ شروع کر دیا.بعد میں حاضرین میں سے کسی نے عرض کیا یا امیر
المومنین! آپ نے یہ کیا فرمایا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ خطبہ کے دوران
اچانک میرے سامنے میدان جنگ کا وہ منظر آ گیا جہاں مسلمان سار یہ جرنیل کی سر کردگی میں لڑ
رہے ہیں (ساریہ اس وقت مسلمان فوج کے سپہ سالار تھے ) اور میں نے دیکھا کہ وہ پہاڑ سے
ہٹے ہوئے ہیں اور خطرہ تھا کہ دشمن مسلمان فوج کو گھیرے میں لے لے.( کیونکہ مسلمان
فوجوں کے مقابل پر دشمن کی تعداد بالعموم زیادہ ہوا کرتی تھی ) تو اس خطرے کے پیش نظر
بے اختیار میں نے سردار شکر کو ہدایت دی.يَا سَارِيَةَ الْجَبَلُ يَا سَارِيَةَ الْجَبَل.اے ساریہ!
پہاڑ کے دامن میں آجاؤ.پہاڑ کے دامن میں آجاؤ.یہ بات ہوئی اور ختم ہوگئی.کچھ عرصے کے
بعد ساریہ کی طرف سے پیغامبر خط لے کر آیا اور اس میں یہ سارا واقعہ درج تھا.خط کا مضمون یہ
تھا کہ اے امیر المومنین! گزشتہ جمعہ کے روز ایک عجیب واقعہ ہوا.ہم جمعرات اور جمعہ کی
درمیانی رات لڑتے رہے یہاں تک کہ دن نکل آیا اور لڑائی جاری رہی اور پھر ہم جمعہ کے
وقت میں داخل ہو گئے.اس وقت ہمیں یہ خطرہ تھا کہ ہم دشمن سے شکست کھا جائیں گے اور پسپا
ہوجائیں گے.تو اچانک ہمیں آپ کی ( حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ) آواز آئی يَا سَارِيَةَ الْجَبَل
يَا سَارِيَةَ الجبل اور سارے لشکر نے یہ آواز سنی.چنانچہ انہوں نے فوری طور پر پہاڑ کے
دامن کا رخ اختیار کیا اور اس طرح اپنی پشت محفوظ کر لی.( چھوٹی فوج کے لیے ہر سمت میں
لڑنا مشکل ہوا کرتا ہے.کوئی نہ کوئی سمت اس کی محفوظ ہونی چاہئے.) اور پشت محفوظ ہوتے ہی
بظاہر مغلوب ہونے والی فوج اچانک غالب آ گئی.اس طرح وہ معرکہ مسلمانوں کے حق میں
ثابت ہوا.تاریخ انمیں جلد نمبر 2 صفحہ 270-271- تاریخ طبری جز 2 صفحہ 553، ذکر فتح جسا دستہ ثلاث وعشرین)
580
Page 589
پس وہ خدا جس نے بدر میں مسلمانوں کی تائید و نصرت کی تھی ، اس نے بعد میں مسلمانوں کو
اپنی تائید سے نوازا.وہ فرشتے جنہوں نے یہ عہد کیا تھا :
نَحْنُ أَوْلِيَتُكُمْ فِي الْحَيَوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ.(حم السجدة32)
انہوں نے پھر اس دنیا کی زندگی میں صحابہ کا ساتھ نہیں چھوڑا.یہی مضمون بغیر ظاہری نظاروں کے یا بغیر کشوف کے یا بغیر رؤیا کے بھی چلتا ہے لیکن اس
قسم کے واقعات جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا انفرادی طور پر بہت زیادہ نہیں ملتے لیکن اس
کے باوجود مجھے یقین ہے کہ بکثرت ایسے واقعات مسلسل رونما ہور ہے ہوں گے کیونکہ جماعت
کی جو تاریخ بن رہی ہے اس میں ہم اس کثرت کے ساتھ فرشتوں کا نزول دیکھتے ہیں کہ یہ
ناممکن ہے کہ صحابہ کے نقش قدم پر چلنے سے یہاں تو بکثرت فرشتے نازل ہو رہے ہوں اور
نعوذ باللہ من ذالک صحابہؓ کی زندگی میں بکثرت نازل نہ ہوئے ہوں.کوئی ایسا ملک نہیں ہے کہ جہاں احمدیت کی تاریخ بن رہی ہے اور اس قسم کے واقعات
وہاں پھیلے نہیں پڑے، بکھرے نہیں پڑے، جیسے کسی نے کہا ہے : ع
چمن میں ہر طرف بکھری پڑی ہے داستاں میری
اسی طرح احمدیت کے چمن میں یہ ایمان افروز نظارے ہر جگہ بکثرت دکھائی دیتے ہیں اور دنیا کا
کوئی خطہ ایسا نہیں جہاں احمدیت داخل ہوئی ہو اور ثبات قدم کے عظیم الشان نمونے اس نے نہ
دکھائے ہوں اور پھر اللہ تعالیٰ کے یہ وعدے بڑی شان کے ساتھ پورے نہ ہوئے ہوں کہ :
تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ
تُوعَدُونَ.(حم السجدة 31)...فرشتوں کے اس قسم کے نزول کے بے شمار واقعات ہیں جو بڑے ہی عظیم الشان اور
دلچسپ ہیں اور احمدیت کی تاریخ کا بہت قیمتی سرمایہ ہیں.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے.تتنالُ..581
Page 590
عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ اور ملائکہ کا یہ وعدہ کہ ہم تمہارے ساتھ رہیں گے ان کے حق میں پورا ہوتا ہے
لیکن یہ وعدہ ایک اور پہلو سے بھی پورا ہوتا ہے جو اس سے زیادہ اہم ہے اور جو مقصود بالذات
ہے، وہ پہلو یہ ہے کہ ملائکہ جن لوگوں کے دوست ہوں ان کا وہ تزکیہ کرتے ہیں.ان کا نفس
پہلے کی نسبت اور زیادہ پاک ہونے لگتا ہے کیونکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ملائکہ گندے لوگوں کے
ساتھ دوستی کر کے بیٹھ جائیں.اور یہ جو وعدہ ہے کہ ہم تمہارا ساتھ چھوڑیں گے نہیں ، اس میں یہ
بھی خوشخبری ہے کہ جو قو میں ابتلاؤں کے دور سے گزرتی ہیں ان کا تزکیہ نفس ہوتا ہے اور ایسا
تزکیہ نفس ہوتا ہے کہ پھر وہ جاری رہتا ہے اور قائم رہتا ہے وہ ایسے اعمال صالحہ کی شکل اختیار
کر لیتا ہے جو ان کا ساتھ نہیں چھوڑتے ، اس کا طبعی نتیجہ نکالا گیا ہے
وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مَنْ دَعَا إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَالِحًا ( حم السجدة34)
یہ وہ لوگ ہیں جو ابتلاؤں کی چکی میں سے کامیابی کے ساتھ گزر کر جاتے ہیں.ان کو فرشتوں
کی معیت نصیب ہوتی ہے.فرشتے کہتے ہیں ہم تمہارے اولیاء ہیں یعنی فخر فرشتے کر رہے
ہوتے ہیں نہ کہ یہ لوگ یہ بھی عجیب طرز کلام ہے، بڑے آدمی کے پاس ہمیشہ چھوٹے آدمی آیا
کرتے ہیں اور ان کی خدمت میں حاضر ہو کر کہتے ہیں کہ ہم تمہارے دوست ہیں تو خدا کے
فرشتے بھی اسی طرح ان لوگوں کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا نے ہمیں اس لئے
تمہارے پاس بھیجا ہے کہ ہم اپنی دوستی تمہارے حضور پیش کریں اور تم ہماری دوستی میں ہمیشہ وفا
پاؤ گے.ہم کبھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑیں گے.اس کا ایک طبعی نتیجہ یہ ہے کہ عمل صالح ان کا ساتھ نہیں چھوڑتا.ان کے اندر جو پاک
تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں وہ ان کا ساتھ نہیں چھوڑا کرتیں اور جن کی پاک تبدیلیاں ان کا ساتھ
چھوڑ دیں ان پر فرشتے نازل نہیں ہوا کرتے.یہ لازم وملزوم چیزیں ہیں اس لئے جو قوم
ابتلاؤں سے گزر کر وقتی طور پر اصلاح پذیر ہو جائے اور کچھ دیر کے بعد پھر انہی برائیوں میں
ملوث ہو جائے اس پر آیت قرآنی نَحْنُ اَولِیتُكُم في الخيوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ کا اطلاق نہیں
582
Page 591
ہوتا کیونکہ جیسا کہ یہاں بیان کیا گیا ہے اور خدا کی بات جھوٹی نہیں ہوسکتی کہ فرشتوں کی معیت
عارضی نہیں وہ اس طرح نہیں آتے کہ پھر چلے جائیں اور جونیکیاں وہ لے کر آتے ہیں ان کو بھی
ساتھ لے جائیں بلکہ یہ آیت ان لوگوں کے حق میں نازل ہوئی ہے جن کے اعمال صالحہ میں
دوام پیدا ہو جاتا ہے.اور اسی گروہ کا اس آیت میں ذکر ہے وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مَن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا کہ
اب بتاؤ ، ان سے زیادہ پیاری بات کرنے والا دنیا میں کون ہوگا؟ اپنے اعمال صالحہ سے ثابت
کر رہے ہیں کہ یہ نیک اور خدا والے لوگ ہیں ، ابتلاؤں سے گزرے ہوئے ہیں، آزمودہ کار
ہیں ، خطرات کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا ہوا ہے اور ان سے کامیابی کے ساتھ گزرے
ہوئے ہیں.ان کی تلخیوں کو برداشت کیا ہوا ہے اور پھر ان
تلخ درختوں کو خدا کی رحمت نے جو
میٹھے پھل لگاتے تھے ان سے لذت یاب ہیں اس لئے ان سے زیادہ پیاری بات کرنے والا اور
کوئی نہیں.اس کے بعد ایک اور دور شروع ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ انگلی چند آیات میں بیان کیا گیا ہے.خطبہ جمعہ حضرت خلیفہ المسیح الرابع رحمہ اللہ فرمودہ 1 فروری 1983ء.خطبات طاہر جلد 2 صفحہ 75 تا85)
اسی تسلسل میں حضور رحمہ اللہ نے خطبہ جمعہ فرمودہ 18 فروری 1983ء ( بمقام مسجد احمدیہ
مارٹن روڈ کراچی) میں ان آیات کی نہایت لطیف تفسیر کرتے ہوئے فرمایا:
قرآن کریم داعی الی اللہ کو اس کے مستقبل کے حالات سے بھی باخبر رکھتا ہے.چنانچہ
قرآن کریم میں ایسا کوئی حکم موجود نہیں ( یہ موقع ہو یا کوئی اور موقع ہو ) جہاں حکم کے نتیجہ میں
پیدا ہونے والی ذمہ داریوں سے آگاہ نہ کیا گیا ہو، اس کے اچھے اثرات سے آگاہ نہ کیا گیا ہو،
اس کے خطرات سے آگاہ نہ کیا گیا ہو، اور پھر خطرات سے بچنے کا طریق نہ سکھایا گیا ہو.پس وہ
آیات جو یہاں سے شروع ہوتی ہیں وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا الشَّيْئَةُ ان میں یہ مضمون بیان
ہوا ہے.583
Page 592
سب سے پہلی بات جو تو جہ کو اپنی طرف کھینچتی ہے وہ یہ ہے کہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا
السَّيِّئَةُ میں لا کی تکرار کیوں ہے.کیونکہ قرآن کریم میں دوسری جگہ جہاں بھی حسنہ اور
سینه کا موازنہ کیا گیا ہے اور یہ کہنا مقصود ہے کہ بھلائی بدی کے برابر نہیں ہوسکتی اور بدی
بھلائی کے برابر نہیں ہوسکتی وہاں ایک ہی لا“ نے دونوں کام کئے ہیں اور عربی قاعدہ کے
مطابق موازنہ کے لئے دو دفعہ لا کی تکرار نہیں ہونی چاہئے.جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں کہ
بدی اور بھلائی ہم پلہ یعنی برابر نہیں ہو سکتے.ایک دفعہ ”نہیں“ کہتے ہیں.یہ نہیں کہتے کہ نہ
بدی برابر ہو سکتی ہے نہ بھلائی برابر ہوسکتی ہے.پس یہ وہ مضمون ہے جس کو اردو میں اس کا متبادل
مضمون بیان کر کے واضح کیا ہے اور بتایا ہے کہ عربی میں اس طرح کی تکرار کا ترجمہ یہ بنے گا کہ نہ
بدی برابر ہوسکتی ہے نہ بھلائی برابر ہوسکتی ہے.اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں حکمت کیا ہے.اس کی حکمت یہ ہے کہ یستوی تستومی کا محاورہ بعض دفعہ مقابلہ کے لئے آتا ہے.بعض
دفعہ بغیر مقابلہ کے لئے استعمال ہوتا ہے.یہ محاورہ ایک جماعت کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے
اور شخص واحد کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے اور اس میں مقابلہ یا موازنہ مقصود نہیں ہوتا.جیسا کہ
اللہ تعالیٰ اپنے متعلق قرآن کریم میں فرماتا ہے.ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ (الاعراف 55)
پھر وہ عرش پر استوئی پکڑ گیا.اور بھی کئی جگہ انہی معنوں میں استویٰ یستوی کا استعمال ہوا
ہے جن میں مقابلہ مقصود ہی نہیں اور اس کے معنی کچھ اور بن جاتے ہیں.پس لا تَسْتَوِی الْحَسَنَةُ بھی اپنی ذات میں ایک مکمل اعلان ہے اور لَا تَسْتَوِی الشَّيْئَةُ
بھی اپنی ذات میں ایک مکمل اعلان ہے جیسا کہ فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ
دراصل یہاں دو الگ الگ اعلان ہو رہے ہیں اس لئے یہاں عربی لغت کے مطابق استویٰ کا
معنی یہ بنے گا کہ نہ تو نیکی کو قرار ہے نہ بدی کو قرار ہے.دونوں اپنی ذات میں Stable یعنی
مستحکم نہیں ہیں.یہ بڑھتی اور گھٹتی رہتی ہیں.ان دونوں کے درمیان ہر وقت ایک مقابلہ جاری
ہے.مثلاً وہ نیکی جس کی تم حفاظت نہ کرو اور جس کو بڑھانے کی کوشش نہ کرو اس کے متعلق اگر تم
584
Page 593
یہ خیال کرو کہ یہ استویٰ کر رہی ہے یعنی وہ اپنے مقام پر ٹھہری رہے گی اور اس کا نقصان نہیں ہوگا
تو یہ غلط فہمی ہے، اس کو دل سے نکال دو.اسی طرح یہ خیال بھی دل سے نکال دو کہ بدی اگر
تمہاری طاقت سے کمزور پڑ گئی ہے تو وہ دوبارہ سر نہیں اٹھا سکتی.قانون قدرت ایسا ہے کہ ان
دونوں کے درمیان ایک مجادلہ، ایک جہاد ہمیشہ سے جاری ہے اور ہمیشہ جاری رہے گا.نہ تو حسن
کو قرار ہے نہ بدصورتی کو قرار ہے.نہ خوبی کو قرار ہے نہ بدی کو قرار ہے.بیہ وہ مضمون ہے جو قرآن کریم بیان کرنا چاہتا ہے اور چونکہ جہاد کا مضمون چل رہا ہے اس
لئے اس موز ونیت سے یہی مضمون ہونا چاہئے.چنانچہ معا بعد صرف جہاد کی طرف لوٹتا ہے.فرماتا ہے ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ اب تمہارا مقابلہ ہو گا.جب تم دنیا کو نیک کاموں کی طرف
بلاؤ گے تو تمہارا مقابلہ شروع ہو جائے گا.یادرکھو یہ مقابلہ تمہارے لئے بہتر ہے.تم جب تک
جہاد میں مصروف رہو گے تمہارا حسن بھی بڑھتا چلا جائے گا اور مقابل کی بدیاں
گھٹتی چلی جائیں
گی.جب تم جہاد سے غافل ہو جاؤ گے تو تمہارے اندرونی حسن کی بھی کوئی ضمانت نہیں دی
جاسکتی کیونکہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ
پھر قانون کیا ہوا.فرما يلادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ جب بھی مقابلہ ہوتو یہ بات یادرکھنا کہ بدی
کے مقابل پر صرف حسن پیش نہیں کرنا بلکہ بہترین حسن پیش کرنا ہے.ایسا حسن کہ جس سے بہتر
اور حسین تصور ممکن نہ ہو.وہ بات نکالو جو بہترین ہو اور اس سے بدی کا مقابلہ کرو.یہ جو احسن دلیل کے ساتھ مد مقابل سے مجادلہ کا سوال ہے یہ بھی دو طرح سے جاری ہوتا ہے
کیونکہ قرآنِ کریم میں اس سے پہلے داعی الی اللہ کے متعلق فرمایا کہ وہ بلاتا بھی ہے اور نیک
عمل بھی کرتا ہے.پس ادفع بالتي هِيَ أَحْسَن کا اطلاق بلانے کی طرف بھی ہوگا اور نیک اعمال
کی طرف بھی ہو گا.گویا ان معنوں میں یہ بات بنے گی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ
جب تمہارا دوسروں کے ساتھ قول میں مقابلہ ہو تو احسن قول سامنے پیش کرو، جب تمہارا اعمال
میں مقابلہ ہو تو احسن عمل مقابل پر پیش کرو.585
Page 594
جہاں تک احسن قول کا تعلق ہے، پھر آگے اس کی شاخیں بنتی ہیں.مثلاً اگر ایک دشمن گالیاں
دیتا ہے، بدزبانی سے کام لیتا ہے تو اس موقع پر یہ آیت ی تعلیم دے رہی ہے کہ اس کے مقابل پر تم
نے بدزبانی نہیں کرنی تم نے گندہ دہنی سے کام نہیں لینا کیونکہ اس لڑائی کے جو اسلوب مسلمان کو
بتائے جارہے ہیں ان میں یہ بات داخل ہی نہیں کہ برائی کا بدلہ برائی سے دیا جائے.مراد یہ ہے
کہ اگر تم اس مقصد کو حاصل کرنا چاہتے ہو جو ان آیات کے آخر پر بیان ہوا ہے تو پھر تمہیں اس
اسلوب جنگ کو اختیار کرنا پڑے گا.جہاں تم اس کو چھوڑ دو گے تو پھر نتائج کے ذمہ دار تم ہو گے.پھر نہ قرآن ذمہ دار ہے نہ وہ ذمہ دار ہے جس نے قرآن کریم کو نازل فرمایا.پس احسن قول میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر قسم کی گندہ دہنی ، گالی گلوچ اور ایذا رسانی کے
مقابل پر اچھی بات کہنا سیکھو.چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں:
گالیاں سن کے دعا دیتا ہوں ان لوگوں کو
رحم ہے جوش میں اور غلیظ گھٹا یا ہم نے
( آئینہ کمالات اسلام روحانی خزائن جلد نمبر 5 صفحہ 225)
یہ ہے قول میں بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ کا ایک عملی نمونہ.اس کا دوسرا پہلو مجادلہ سے تعلق رکھتا ہے.جب دلائل کی جنگ شروع ہو تو پہلے کمز ور دلائل
نہ نکالا کرو یا یوں ہی کوئی دلیل دینی نہ شروع کر دیا کرو بلکہ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ کی رو سے تم
اپنے ترکش سے سب سے اچھا تیر نکالو، سب سے مضبوط دلیل نکالا کرو اور یہ ایک بہت بڑی
حکمت کی بات ہے.بعض دفعہ لوگ کسی مضمون کے بارہ میں ایک سے زائد دلائل سیکھ جاتے
ہیں اور پھر اس بات کا امتیاز کئے بغیر کہ وہ کس دلیل کو زیادہ عمدگی سے پیش کر سکتے ہیں ایک،
دو، تین گنتی بڑھاتے چلے جاتے ہیں.اور یہ امر واقعہ ہے کہ ہر ہتھیار کو ہر شخص پوری مہارت
سے استعمال نہیں کر سکتا.اگر ہتھیار اچھا بھی ہو تب بھی اس کے استعمال کرنے کا ڈھنگ تو آنا
چاہئے.بعض قوموں نے ہتھیاروں میں بالا دستی کے باوجود بعض دفعہ عبرتناک شکستیں کھائی
586
Page 595
ہیں کیونکہ ان کو ہتھیار کا استعمال نہیں آتا تھا.چنانچہ 1967ء کی مصر اسرائیل جنگ میں رشیا
کی طرف سے مصریوں کو بڑے Sophisticated Weapons عمدہ اور ترقی یافتہ
ہتھیار دئیے گئے تھے لیکن مصریوں کو ابھی ان کا استعمال کرنا نہیں آیا تھا.نتیجہ یہ ہوا کہ دشمنوں
نے ان ہتھیاروں پر قبضہ کیا اور پھر ان کو مصریوں کے خلاف استعمال کیا.پس احسن دلیل سے صرف یہ مراد نہیں کہ دلیل فی ذاتہ مضبوط ہو بلکہ اس کو پیش کرنے کا
ڈھنگ بھی احسن ہو اور اس پر پوری طرح عبور بھی حاصل ہو.اس پہلو سے جب ہم تربیتی کلاسز
منعقد کرتے ہیں تو ہمیں حکمت کے اس نکتے سے اس موقعہ پر بھی زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانا
چاہئے.کوئی بھی طالب علم جس کو ایسی کلاسوں میں جانے کا تھوڑا سا وقت ملتا ہے ، اس کو
بجائے اس کے زیادہ سے زیادہ دلائل سمجھائے جائیں جن سے فائدہ کی بجائے آہستہ آہستہ
ذہن Confuse یعنی خلط مبحث پیدا ہو جائے ، کوشش کی جائے کہ قرآنی تعلیم کے مطابق
ایک چوٹی کی دلیل چنی جائے جو اس کو یاد کروائی جائے.اس میں اسے صیقل کیا جائے اس
کے سارے پہلو ذہن میں اجاگر کئے جائیں تا کہ وہ اسے زیادہ عمدگی کے ساتھ استعمال کر سکے اور
پھر اس دلیل پر جو حملہ ہوتا ہے اس کا جواب بھی تفصیل سے سمجھایا جائے.گویا ایک دلیل کو لے
کر اس پر پوری مہارت پیدا کر دی جائے تو یہ ادفع باليني هِيَ أَحْسَن کے حکم کی اطاعت ہوگی...غرض ادفع بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ کے تابع ہر احمدی جو داعی الی اللہ بننا چاہتا ہے اس کو پہلے
تمام اختلافی مسائل کی کوئی ایک دلیل چن لینی چاہئے.لیکن وہ دلیل چنی چاہئے جس پر وہ ذہنی
اور علمی لحاظ سے خوب عبور حاصل کر سکتا ہو اور شروع میں اپنے علم کو بہت زیادہ نہ پھیلائے.یہ
بعد کی باتیں ہیں.فی الحال تو سب سے قوی دلیل وفات مسیح کی ہے.سب سے عمدہ تشریح
قرآن کریم کی آیت خاتم النبیین کی ہے اور اسی طرح دیگر مسائل مثلاً صداقت حضرت مسیح موعود
علیہ الصلوۃ والسلام کے موضوع پر ایک ایک دلیل کو چنیں اور اس پر عبور حاصل کریں.ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ کا تیسرا پہلو یہ ہو کہ جب مناظرہ شروع ہو، گفتگو شروع ہو تو تمہارا یہ
کام نہیں ہے اور تمہاری گفتگو کا یہ مقصد نہیں ہے کہ تم دوسرے کو نیچا دکھاؤ اور اس کی تذلیل کرو
587
Page 596
کیونکہ قول کا حسن جاذبیت کے معنی رکھتا ہے اس لئے تم جس بات کو پیش کروا سے اس طرح
پیش کرو کہ لوگوں میں اس کے لئے کشش پیدا ہو نہ کہ نفرت میں اور بھی انگیخت ہو جائے.پس
یہ پہلو بھی قول کے حسن کے ساتھ بڑا گہرا تعلق رکھتا ہے.احسن کہ کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا
تمہاری گفتگو کا طریق نہایت عمدہ ہونا چاہیئے.ایسی گفتگو کریں جس میں تقویٰ ہو، سچائی ہو، گہرائی
ہوا اور وزن ہو.لوگوں کو صداقت از خود جھلکتی ہوئی نظر آ رہی ہو.دیکھنے والے عش عش کر اٹھیں
اور بے اختیار کہنے لگیں کہ یہ تو سچائی بول رہی ہے اور وہ ان کو قبول حق پر مجبور کردے.چنانچہ
حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سے صحابہ کم علمی کے باوجود اس لئے کامیاب مبلغ
تھے کہ ان کی بات میں وزن تھا، ان کے اندر سچائی تھی ، ان میں سادگی تھی اور سادگی بجائے خود
ایک قوت تھی.ان چیزوں نے مل کر ان کی زبان میں اور ان کے قول میں ایک حسن پیدا کر دیا
تھا.ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَن کا جو نتیجہ قرآن کریم بعد میں ذکر کرتا ہے وہ نتیجہ ان کو حاصل ہوا.داعی الی اللہ کا دوسرا پہلو اعمال کو حسین بنانے سے تعلق رکھتا ہے کیونکہ دو باتیں بیان فرمائی
تھیں.ایک یہ کہ مومن داعی الی اللہ ہوتا ہے.دوسرے یہ کہ عمل صالحا یعنی وہ نیک اعمال بھی
بجالاتا ہے.گویا نیک اعمال کو اس طرح ادا کرتا ہے کہ وہ احسن بن جائیں.یہاں نیک اعمال
بمقابلہ بداعمال مراد ہیں.یہ ایک مقابلہ کی صورت ہے جو یہاں پیش کی گئی ہے.مثلاً لوگ مال
لوٹتے ہیں،گھر جلاتے ہیں، طرح طرح کے دکھ دیتے ہیں اسکے باوجود اپنے دل کو اس بات پر
آمادہ رکھنا اور اس کی ایسی تربیت کرنا کہ خود دشمن جب دکھ میں مبتلا ہو تو اس کی مدد کی جائے گویا
اعمال کے لحاظ سے یہ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ کی ایک بہترین صورت ہے.ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ کا دوسرا پہلو اندرونی تربیت سے بھی تعلق رکھتا ہے.فرمایا جب بھی
تمہارے اندر کوئی برائی پیدا ہونے لگے تو اس کو حسن سے دور کرو اور جب بھی معاشرہ میں
تربیت کے معاملہ میں کوئی برائی پیدا ہو اس کو بھی حسن سے دور کرو.یہ مضمون بھی اپنی ذات میں بڑا گہرا اور تفصیلی ہے.قرآن کریم نے کہیں بھی
Annihilism یعنی ملیا میٹ کر دینے کا کوئی فلسفہ پیش نہیں کیا.قرآن کریم نے کہیں بھی کسی
588
Page 597
کو یہ تعلیم نہیں دی کہ وہ کسی موجود چیز کو مٹادے.ہاں بہتر چیز سے بدلہ دینے کی تعلیم دیتا
ہے.لیکن سارے قرآن کریم میں کسی ایک جگہ بھی Annihilism یعنی ملیا میٹ کر دینے کی
تعلیم نہیں دی گئی.یہ کہنا کہ :
اٹھو مری دنیا کے غریبوں کو جگادو
کاخ امراء کے درودیوار ہلا دو
( بال جبریل نظم بعنوان فرمان خدا)
قرآن کریم میں ایسی کوئی تعلیم نہیں ملتی.یہ شاعروں کی دنیا کی باتیں ہے.قرآن کریم ی تعلیم
دیتا ہے کہ اگر تم میں بہتر چیز دینے کی طاقت موجود ہے تو بری چیز کو بہتر چیز سے تبدیل کرو.اگر تم میں یہ طاقت موجود نہیں ہے تو پھر تمہیں اس بات کا کوئی حق نہیں کہ ایک موجود چیز کو
مٹاؤ کیونکہ اس طرح خلا پیدا ہوتا ہے جس کی سارے قرآن میں کوئی تعلیم نہیں ہے.پس ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ کا یہاں مطلب یہ بنے گا کہ برائیوں کوحسن سے Replace
یعنی بدل دو.حسن داخل کرتے چلے جاؤ تا کہ برائیاں جگہ چھوڑتی چلی جائیں.جیسے ایک کمرہ
میں زیادہ لوگوں کے بیٹھنے کی گنجائش نہ ہو تو جو لوگ پہلے بیٹھے ہوتے ہیں وہ نئے آنے والوں کے
لئے جگہ خالی کرنا شروع کر دیتے ہیں.یہاں بھی اسی قسم کا مضمون ملتا ہے.اللہ تعالیٰ فرماتا
ہے تم اپنی طبیعت میں حسن داخل کرتے چلے جاؤ، بدیاں خود بخو دجگہ چھوڑتی چلی جائیں گی اور یہ
امر واقعہ ہے کہ اس کے بغیر کبھی دنیا میں کوئی باقی رہنے والی تربیت نہیں ہوسکتی.جولوگ اس
نفسیاتی نکتے کو نہیں سمجھتے وہ ہمیشہ بدیاں دور کرنے میں ناکام رہتے ہیں کیونکہ انسانی فطرت کا یہ
تقاضا ہے کہ جب کسی کو یہ کہا جائے کہ یہ نہ کرو تو سوال یہ ہے کہ کیوں نہ کرے، اس سے بہتر
کوئی چیز ملے گی تو نہیں کرے گا اور نہ وہ اپنی ضد پر قائم رہے گا.فطرت چاہتی ہے کوئی اس کا
متبادل ہو، کوئی اس سے بہتر چیز ہو اس لئے میں نے بارہا یہ کہا ہے کہ آپ جب اپنے گھروں
کی، اپنے بچوں کی ، اپنی عورتوں کی تربیت کرتے ہیں تو اس بات کو پیش نظر رکھا کریں کہ اگر
ان کو میوزک سے ہٹانا ہے یا گندی قسم کے گیتوں سے اور گندے فلمی گانوں سے ہٹانا ہے تو
589
Page 598
پہلے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی نظمیں اچھی آواز میں تیار کریں جو دل پر گہرا اثر
کرنے والی ہیں.جب آپ وہ نظمیں ان کو سنانا شروع کریں گے تو آہستہ آہستہ ان کی لذتوں
کے معیار بدلنے شروع ہوں گے.ایک چیز داخل ہوگی دوسری کو دھکیل کر باہر کر رہی ہوگی.یہ ایک دن کا کام نہیں ہے، دو دن کا کام نہیں ہے، یہ تو بڑا لمبا اور صبر آزما کام ہے.ہمت کے
ساتھ اور مستقل مزاجی کے ساتھ انسان اگر ایک پروگرام بنا کر رفتہ رفتہ یہ کام کرنا چاہے تو یقیناً
کامیاب ہوگا کیونکہ قرآن کریم کا یہ دعویٰ ہے اور قرآن کریم کا دعویٰ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا.آپ Creative Programme یعنی تعمیری پروگرام بنائیں.یاد رکھیں اگر آپ
میں تعمیری پروگرام بنانے کی اہلیت نہیں ہے تو دنیا آپ کی بات نہیں مانے گی.چنانچہ انبیاء
علیہم السلام کی تعلیم اور ان کے دستور سے جو قرآن کریم میں بیان ہوا ہے ہمیں یہی معلوم ہوتا
ہے کہ اس عمل میں وہ اس بات کا انتظار نہیں کیا کرتے تھے کہ مقابل کی سوسائٹی پہلے ایمان
لائے تو پھر ان کے اندر حسن عمل پیدا کرنے کی کوشش شروع کی جائے.قرآن کریم میں
ایسے جتنے بھی واقعات بیان ہوئے ہیں ان سے پتہ لگتا ہے کہ برائیوں کو دور کرنے کی تعلیم وہ
پہلے شروع کر دیتے تھے....انبیاء نے قوم کے عمل کو درست کرنے کے لئے کبھی اس بات کا
انتظار نہیں کیا کہ وہ لوگ ایمان لاتے ہیں یا نہیں.اس میں ایک گہری حکمت ہے اور وہ
حکمت یہ ہے کہ نیکی کی بات دراصل کسی دلیل کو نہیں چاہتی کسی اچھے اور خوبصورت کام کی طرف
اگر آپ خوبصورت رنگ میں کسی کو بلاتے ہیں تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم کب تمہیں مانتے ہیں
کہ تم ہمیں یہ باتیں کہتے ہو.اگر کوئی یہ جواب دے تو اس کی بڑی بیوقوفی ہو گی.آپ کسی
بھو کے آدمی کو یہ کہیں کہ میں تمہارے لئے کھا نالا یا ہوں تم کھانا کھالو تو وہ یہ نہیں پوچھے گا کہ میں
تو تمہیں مانتا ہی نہیں، میں کیوں کھانا کھالوں.کوئی آدمی گرمی میں دھوپ میں بیٹھا ہو اور آپ
اس سے
کہیں کہ اٹھ کر سایہ میں آجاؤ تو وہ آگے سے یہ جواب نہیں دے گا کہ نہیں انہیں ! تم اور
فرقہ سے تعلق رکھتے ہو میں اور فرقہ سے تعلق رکھتا ہوں.اچھی باتوں میں فرقہ کا سوال ہی پیدا
نہیں ہوتا.نظریاتی اختلاف الگ ہیں ان کا اپنا مقام ہے اور نیک اعمال کی تعلیم ایک بالکل
590
Page 599
الگ مسئلہ ہے اس لئے اس معاملہ میں انبیاء نے کبھی انتظار نہیں کیا اور اس میں ایک بڑی
حکمت یہ تھی کہ ان کا اور سوسائٹی کا فاصلہ زیادہ نہیں ہوا.اگر آپ اپنے ماحول کو گندہ ہونے دیں
اور اجازت دے دیں کہ وہ جو رخ چاہتا ہے اختیار کرلے اور انتظار کریں کہ جب تک وہ قبول
نہیں کرتا اس وقت تک آپ نے ان کے اندر حسن پیدا نہیں کرنا تو آپ میں اور اس ماحول
میں جتنے فاصلے بڑھتے چلے جائیں گے اتنے آپ کے مسائل بڑھتے چلے جائیں گے.یہ
بے اعتنائی واپس الٹتی ہے اور یہی گندہ ماحول پھر آپ کے گھر کو تباہ کرتا ہے.یہ ایسی
بے اعتنائی نہیں ہے جس کو خدا بخش دے گا بلکہ بے اعتنائی کرنے والی قوم کو اس بے
اعتنائی کی سزادی جاتی ہے کیونکہ مخالف معاشرہ بدیوں میں جتنا آگے بڑھتا ہے وہ ساتھ ساتھ
آپ سے اپنا ٹیکس وصول کرتا ہے اور آپ کے معیار کو بھی بھینچ کر نیچے لے جارہا ہوتا ہے اس
لئے قرآن کریم نے انبیاء کا جو پاک نمونہ محفوظ کیا ہے اس کا یہی مقصد تھا کہ جو قو میں بھی داعی
الی اللہ بننا چاہتی ہیں وہ اپنے معاشرہ کی درستی کا انتظام اس بات کا انتظار کئے بغیر شروع کر دیں
کہ وہ لوگ ایمان لاتے ہیں یا نہیں.یہ ساری باتیں وہ ہیں جن کے نتیجہ میں انسان کو دکھ ملتے
ہیں.قرآن کریم نے عجیب نتیجہ نکالا ہے.لیکن قرآن کریم جب یہ نتیجہ نکالتا ہے اور اس طرف
توجہ دلاتا ہے تو پہلے اس طریق کار کے عظیم الشان پھل کی طرف بھی توجہ دلاتا ہے.فرماتا ہے
کہ اگر تم اس طریق پر کار بند ہو جاؤ ، اس طریق پر گامزن ہو جاؤ تو ہم تمہیں ایک ضمانت دیتے
ہیں اور وہ یہ ہے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِی حَمیمہ کہ وہ جو پہلے تمہاری جان کا
دشمن تھا وہ تمہارا جاں نثار دوست بن جائے گا اور یہی وہ اعلیٰ مقصود ہے جس کو ایک داعی الی اللہ
حاصل کرنا چاہتا ہے.یہی اس کی کامیابی کا نشان یا تمغہ ہے جو اسے عطا ہوگا.نفرتیں محبتوں میں
تبدیل کی جائیں گی، جان کے دشمن جانثار دوستوں میں تبدیل کئے جائیں گے اور یہ ساتھ ہی
ایک کسوٹی بھی ہے یعنی اگر تبلیغ کے نتیجہ میں یہ واقعات رونما نہیں ہوتے تو اس تبلیغ میں کوئی
خرابی ہے.اگر کسی تبلیغ کے نتیجہ میں ایسے واقعات رونما ہورہے ہیں تو یقینا یہی وہ صحیح طریق
ہے جس پر تبلیغ کی جارہی ہے.لیکن ساتھ ہی تو جہ دلائی کہ یہ ایسا آسان کام نہیں ہے کہ ادھر تم
591
Page 600
منہ سے اچھی باتیں نکالو تو اچانک وہ لوگ تمہارے دوست بن جائیں گے.ویسے اچا نک کا
لفظ موجود ہے.فَإِذَا الَّذِی میں اچانک پن پایا جاتا ہے لیکن اس کا معنی اور ہے، وہ میں بعد
میں بتاؤں گا.غرض یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ادھر تم نے منہ سے بات نکالی اور ادھر وہ تمہارے دوست
بن گئے کیونکہ اچانک پن کا صبر سے کوئی جوڑ نہیں یعنی اس اچانک پن کا کہ ادھر تم نے کام
شروع کیا ادھر نتیجہ نکل آیا اس کا صبر سے کیا تعلق ہے.مگر قرآن کریم معابعد فرماتا ہے.وَمَا
يُلْقَاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا اس نتیجہ کو صبر کرنے والوں کے سوا کوئی حاصل نہیں کر سکتا.پھر
اچانک پن کا کیا مطلب ہے اور صبر کا مضمون کیا ہے؟ اب اس کو میں کھولوں گا تو بات سمجھ
آجائے گی.بات یہ ہے کہ ہر نصیحت کا رستہ ایک صبر آزما مشکل کا رستہ ہوتا ہے.جب کوئی شخص کسی کو
بلاتا ہے تو اس کے دوطریق ہیں.یا تو اس شخص کے ساتھ آپ کی دوستی ہے اور یا دشمنی ہے.اگر دوستی ہے تو زیادہ نصیحت کرنے کے نتیجہ میں دوستیاں بھی ٹوٹ جایا کرتی ہیں.آپ اپنے
دوستوں کو بار بار نصیحت کر کے دیکھیں تھوڑی دیر کے بعد وہ کہنا شروع کردیں گے، کیا تم نے
کان کھانے شروع کر دئیے ہیں یار چھوڑو بھی ، اب بس بھی کرو.پھر زیادہ سختی کرنی شروع
کریں گے تو وہ کہیں گے بند کرو یہ کیا رٹ لگائی ہوئی ہے.پھر کہیں گے جاؤ جہنم میں ہمارا دین
الگ ہے تمہارا الگ ہے.ہم جو چاہیں کریں تم کون ہوتے ہو ہمیں نصیحتیں کرنے والے.پس تجربہ کر کے دیکھ لیں اس طرح بظاہر الٹ نتیجہ نکلتا ہے یعنی آپ جتنی نصیحت کرتے ہیں
اتنی دشمنیاں بڑھتی ہیں اور پھر انبیاء کے زمانہ میں تو یہ بہت شدت اختیار کر جاتی ہیں کیونکہ باوجود
دوستی کے نصیحت کا مضمون بہت بلند ہو جاتا اور جس چیز کی طرف بلایا جاتا ہے وہ اتنی مختلف ہوتی
ہے اس چیز سے جس پر وہ قومیں پائی جاتی ہیں کہ اس فاصلہ کے نتیجہ میں بھی بڑی شدت سے نفرت
پیدا ہو جاتی ہے.592
Page 601
اب دیکھئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت کا پیغام لائے ہیں، سب سے
زیادہ احسن قول آپ کا قول تھا ، سب سے زیادہ احسن عمل آپ کا عمل تھا، اس کے باوجود سب
سے زیادہ مخالفت آپ سے کی گئی.تو پھر فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ مَا
کیا مطلب ہوا ؟ اس مضمون کو صبر نے کھولا ہے.فرمایا شروع میں ایسا ہی ہو گا جب تم نیک
کاموں کی طرف بلانا شروع کرو گے تو شروع میں قوم کا اسی قسم کا ردعمل ہوگا.تمہاری محبتوں
کے نتیجہ میں شدید نفرتیں پیدا ہوں گی لیکن اگر تم متزلزل نہ ہوئے ، اگر تم اپنی محبت پر قائم رہے،
اگر اپنے قول اور فعل کے حسن پر قائم رہے تو پھر اس صبر کے نتیجہ میں ڈالذینی والا واقعہ رونما
ہوگا.اور جب ایسا ہوگا تو تمہیں یوں لگے گا جیسے اچانک ہو گیا ہے.حالانکہ صبر اندر ہی اندر
مخالفتوں کو کھا جایا کرتا ہے.صبر میں بڑی قوت ہے.یہ عجیب بات ہے کہ صبر کرنے والے کی
دعائیں اور کوششیں جب پھل لاتی ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے اچانک پھل لگ گیا ہے.اس
تأثر کو ظاہر کرنے کے لئے قرآن کریم نے فرمایا فإذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ دوسرے
إِذَا الَّذِی میں ایک اور مضمون بھی ہے.اِذَا الَّذینی اچانک پن کے علاوہ ایک غیر معمولی واقعہ
کی تحسین کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے کہ دیکھو دیکھو کیساشاندار نتیجہ نکلنے والا ہے.ان معنوں
میں بھی اذا الذینی استعمال ہوتا ہے.تو دوسرے معنی اس کے یہ بنیں گے کہ دیکھو ان کوششوں
کا کیسا عظیم الشان نتیجہ نکلا ہے.ہم جو تمہیں کہتے تھے کہ یوں کرو تو یونہی نہیں کہتے تھے.حیرت انگیز انقلاب بر پا کرنے والا مضمون تھا.فرمایا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ دیکھنا
کتنا عظیم الشان انقلاب بر پا ہو گیا کہ تمہارے خون کے دشمن جاں نثار دوست بن گئے.میں اس وقت چند ایک باتیں صبر کے مضمون میں بیان کرنا چاہتا ہوں.پہلی بات تو یہ ہے
کہ صبر دونوں جگہ ہے یعنی قول میں بھی اور عمل میں بھی.جو بات کہنے کی ہے وہ کہتے چلے جانا
ہے.یہ ہے قول کا صبر اور جو حسن عمل ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹنا.آزمائش جتنی مرضی سخت
ہوتی چلی جائے تم نے اپنے اعمال کے حسن کو بدی میں نہیں تبدیل ہونے دینا.یہ دو قسم کے
593
Page 602
صبر تمہیں اختیار کرنے پڑیں گے.جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا چند اشارے کرتے ہوئے
میں آگے چلتا ہوں.اس مضمون کو جب آپ کھولیں گے تو بہت سی کام کی باتیں اور بڑی حکمت
کی باتیں آپ کے ہاتھ میں آئیں گی.دوسرے صبر کا مضمون یہ بتاتا ہے کہ تم تو محبت کر رہے ہو گے وہ تمہیں دکھ دے رہے ہوں
گے اور اس دکھ کے نتیجہ میں تمہارے اندر کوئی ایسی قوت پیدا ہونی چاہئے جس سے تمہیں وہ غلبہ
نصیب ہوگا جس کی طرف ہم تمہیں بلارہے ہیں یا جس کا ہم تم سے وعدہ کر رہے ہیں.صبر کس قوت میں ڈھلا کرتا ہے؟ یہ اصل سوال ہے.اگر صبر سچا ہے اور وہ شخص اپنے دعویٰ
میں سچا ہو کہ وہ اپنے نفس کی خاطر کسی کی بھلائی نہیں کر رہا بلکہ دوسرے کی بھلائی کی خاطر وہ کر رہا
ہے اور جس کے لئے کوئی کام کر رہا ہو اس کے لئے رحم کا اور شفقت کا اور محبت کا حقیقی تعلق ہو تو
پھر جب وہ دوسرا انکار کرتا ہے تو صبر ہمیشہ اس کے لئے دعا میں تبدیل ہوا کرتا ہے، عفصہ میں
تبدیل نہیں ہوا کرتا.ماں جب بیٹے کو نصیحت کرتی ہے اور وہ ضد کرتا ہے اور کہنا نہیں مانتا تو
کوئی جاہل ماں ہوگی جو اس پر لعنت ڈالنا شروع کر دے ورنہ ہم نے تو یہی دیکھا ہے کہ مائیں
پھر روتی ہیں، اپنی جان ہلکان کر رہی ہوتی ہیں، راتوں کو اٹھ اٹھ کر دعائیں کرتی ہیں اور دوسرے
لوگوں کو دعا کے لئے خط لکھتی ہیں کہ میرا بچہ تباہ ہورہا ہے دعا کریں نیک بن جائے.پس صبر سے جو عظیم الشان قوت پیدا ہوتی ہے وہ دعا کی قوت ہے.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم
محض اپنی باتوں پر اور نیک اعمال پر انحصار نہ کرنا.جب ان باتوں پر صبر کرو گے پھر بھی تمہیں
دکھ دئیے جائیں گے اور صبر لازماً دعاؤں میں ڈھلے گا اور وہ دعائیں عظیم الشان نتیجہ پیدا کریں
گی.چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو فرمایا ہے کہ عرب کے بیابان میں جو
ایک ماجرا گزرا کہ صدیوں کے مردے زندہ ہو گئے اور پشتوں کے بگڑے الہی رنگ پکڑ گئے
جانتے ہو وہ کیا تھا وہ ایک فانی فی اللہ کی دعائیں ہی تو تھیں.( برکات الدعا روحانی خزائن جلد
6 صفحہ 11) ایسی دعائیں صبر کے نتیجہ میں پیدا ہوتی ہیں.بے صبر تو اپنے دل کی بات غصہ کے
594
Page 603
ذریعہ نکال لیتا ہے، اس کے آنسو کہاں سے نکلیں گے جو گالی کے ذریعہ جواب دے کر اپنا دل
ٹھنڈا کر بیٹھا ہو، سامنے بات کرنے سے ڈرتا ہو تو پیچھے گھر میں آکر ہزار بڑبڑ کرے کہ یہ بکواس
اس نے کی، یہ کیا اور وہ کیا ، تو اس بیچارے کو کہاں سے تو فیق ملنی ہے کہ رات کو اٹھ کر روئے.لیکن جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ صرف خدا کی خاطر مجھے مار پڑی ہے، صرف خدا کی خاطر مجھے
تکلیف دی گئی ہے اور خاموش رہتا ہے اور اپنی توجہ کو اپنے رب کی طرف پھیرتا ہے کہ اے
اللہ ! میں تیری خاطر مارا گیا، میں تیری خاطر ذلیل ہوا مگر میں صبر کرتا ہوں ، تب اندر ہی اندراس
کا دل ایسا کھلنے لگتا ہے کہ پھر جب وہ رات کو اٹھتا ہے تو اس کے آنسو بے اختیار نکلتے ہیں.ایسی حالت میں اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کی آواز ایسے درد کے ساتھ اور ایسی ہوک کے
ساتھ اٹھتی ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ بارگاہ الہی میں مقبول نہ ہو.پس تبلیغ کا صبر سے گہرا تعلق ہے اور صبر بھی وہ صبر جو دعا پر منتج ہو جائے.جو دردناک دعاؤں
میں تبدیل ہو جائے.تب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ.تمہیں یوں
محسوس ہوگا جیسے اچانک انقلاب آ گیا ہے تم حیران رہ جاؤ گے کہ یہ کیا واقعہ ہو گیا کل تک تو
گالیاں دینے والے تھے آج ان کو کیا ہو گیا اور یہ واقعات پہلے بھی رونما ہوئے ہیں آج بھی
ہو سکتے ہیں اور ہوتے ہیں لیکن ان کی اعلیٰ مثال کے طور پر مضمون کو مختصر کرتے ہوئے آخر پر
قرآن کریم ایک ایسی بات بتاتا ہے جو ساری باتوں کی جامع ہے اور تمام نصیحتوں کا منبع اور
سرچشمہ ہے.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا يُلَقَاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُوحَةٍ
عَظِیم کہ تم میں سے جو بھی صبر کرے گا وہ بھی یہی پھل پائے گا لیکن حقیقت یہ ہے کہ جیسا
ذُو حظ عظیم کو یہ نتیجہ ملا ویسا کسی کو نہیں مل سکتا.یہ ذُو حظ عظیم کون ہے؟ حضرت
محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں.کیونکہ آپ نے سب سے زیادہ صبر کا نمونہ دکھایا ہے
ذُوحَظ عَظِیمٍ اس شخص کو کہتے ہیں جس نے صبر میں سب سے زیادہ حصہ پایا ہو.عام صبر
کرنے والے بھی ہیں ان کو بھی خدا پھل سے محروم نہیں رکھے گا لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم
595
Page 604
سیکھنا چاہتے ہو کہ صبر ہوتا کیا ہے تبلیغ کس طرح کی جاتی ہے، دعوت الی اللہ کیا ہوتی ہے ، عمل
صالح کیا ہوتا ہے اور بدی کو حسن میں تبدیل کرنے کا مضمون کیا ہے؟ تو خلاصہ کلام یہ کہ
ذُو حَطٍ عَظیم یعنی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو.وہ صرف صبر میں ذُو حظ عظیم نہیں
ہیں بلکہ اس مضمون کی ہر شاخ میں ذُو حظ عظیم ہیں.داعی الی اللہ کے لحاظ سے بھی دعوت کا
سب سے بڑا حصہ آپ کو عطا کیا گیا.عمل صالح کے لحاظ سے بھی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ
علیہ وسلم ہی ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ بنتے ہیں.اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ کے مضمون کے لحاظ سے بھی
حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ذُو حظ عظیم بنتے ہیں اور پھر وہ پھل پانے کے لحاظ سے
کہ اچانک دشمن دوستوں میں تبدیل ہوئے اس لحاظ سے بھی آپ ذُو حظ عظیم بنتے ہیں اور
صبر کے اعلیٰ مظاہروں کے لحاظ سے بھی آپ ذُو حَق عَظِیمٍ بنتے ہیں.پس سیرت طیبہ جو تبلیغ کا طریق سکھاتی ہے اس طرف انگلی اٹھا کر بات ختم کر دی.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق یہ تھا کہ ہمیشہ تبلیغ کے نتیجہ میں جب آپ کو دکھ دئیے گئے
تو نہ آپ تبلیغ سے باز آئے نہ دکھ دینے والوں کو بددعائیں دیں ، نہ ان سے خوف کھایا اور نہ
کسی پہلو سے بھی اپنا پیغام پہنچانے سے باز آئے.باوجود اس کے کہ سوسائٹی نے آپ کا انکار
کیا، آپ سوسائٹی میں حسن پیدا کرتے چلے گئے اور یہ عمل جاری رہا یہاں تک کہ آپ کے ساتھ
اور صبر والے شامل ہو گئے اور دکھ اٹھانے والے ملنے شروع ہو گئے اور دکھ اٹھانے والوں کا یہ
قافلہ آگے بڑھتا چلا گیا یہاں تک کہ وہ انقلاب آیا جس کے متعلق فرمایا کہ تم یہاں بیٹھ کے آج
مڑا کر تاریخ کو دیکھتے ہو تو سمجھتے ہو اچانک ہو گیا اچانک نہیں ہوا تھا.اس کے پیچھے تو بہت خون
بہائے گئے تھے، امنگوں کے خون، جذبات کے خون، اپنے عزیزوں کے خون دینے سے دریغ
نہیں کیا گیا تھا، اپنی تمام خواہشات ان اعلی مقاصد کی بھینٹ چڑھا دی گئیں تھیں یہ صبر جب لمبا
ہوا تب اللہ تعالیٰ کی قدرت نے وہ پھل لگایا جس کے متعلق فرماتا ہے.فرماتا ہے
فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ - آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں یہ عظیم الشان
596
Page 605
انقلاب جس شان سے ظاہر ہوا ہے کسی نبی کی تاریخ میں اس کا عشر عشیر بھی آپ کو نظر نہیں آئے
گا.حیرت انگیز انقلابات ہیں، شدید دشمنوں کا عظیم دوستوں میں تبدیل ہو جانے کی بکثرت
مثالیں ہیں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے.حسن عمل میں حکمت بھی ضروری ہے.حکمت کے ساتھ ایسا فعل کریں جو صرف ظاہر میں اچھا نظر
نہ آئے بلکہ اس کے حسن میں گہرائی ہو.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کسی بھی حکمت کا دامن چھوڑ
کر کوئی فیصلہ نہیں کیا کرتے تھے ہر فیصلہ کے پیچھے حکمت کارفرما ہوتی.آپ کا ہر فیصلہ بڑا گہرا اور
حکمت کا سر چشمہ دکھائی دیتا ہے.آپ کسی واقعہ پر ٹھہر کر غور کریں اور اس کے اندر تہ تک غوطہ
ماریں آپ کو موتی مل جائیں گے.آپ تلاش کریں آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایک واقعہ بھی
ایسا نہیں جس کے اندر گہرے حکمت کے موتی پوشیدہ نہ ہوں.غرض یہ وہ طریق تبلیغ ہے جو قرآن کریم نے سکھایا اور یہ وہ نتائج ہیں جو قرآن کریم کے بیان
کے مطابق لازماً نکلا کرتے ہیں.حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ میں بھی نکلے.ہم نے بھی اپنی آنکھوں سے بارہا یہ نتیجے نکلتے دیکھتے ہیں.ابھی چند ہفتے ہوئے لاہور میں اکٹھے
بیٹھنے کا موقعہ ملا.کسی گھر میں مدتوں سے ایک خاتون رہ رہی تھیں وہ احمدی نہیں ہوتی تھیں.مطالعہ بھی کرتی رہیں بخشیں بھی کرتی رہیں.اب جب وہ احمدی ہوئیں تو اس وقت پھر اس آیت
فرماتا ہے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ کا جلوہ ہم نے دیکھا.چنانچہ وہ احمدی ہونے کے
بعد کئی دن روتی رہیں کہ میں احمدی تو ہوگئی ہوں مگر جو میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو
گالیاں دیا کرتی تھی میں بخشی بھی جاؤں گی یا نہیں.مجھے یہ دکھ ہو رہا ہے.شدید بے قرار تھی.ان
کے گھر والوں نے تسلی دی ، پیار کا سلوک کیا، تب بڑی مشکل سے ان کو اطمینان نصیب ہوا.پس یہ کوئی ایسی آیت نہیں جو گزشتہ زمانہ سے تعلق رکھتی ہو.یہ تو ایک جاری وساری زندہ
آیت ہے کیونکہ وہ لوگ جن کے ساتھ اس کا واسطہ تھا وہ مسلسل حسن سلوک کرتے رہے،
انہوں نے مخالفتیں بھی برداشت کیں، گالیاں بھی سنیں لیکن انہوں نے کوڑی کی بھی پرواہ نہیں
597
Page 606
کی ، اپنے حسن سلوک میں کوئی کمی نہیں کی اور جیسا کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے صبر کو ہمیشہ میٹھے پھل
لگتے ہیں، وہ میٹھے پھل بھی ہم نے دیکھے.یعنی شدید مخالفت کرنے والے لوگ اچانک
جاں نثار دوست بن گئے.غرض اس طریق پر اگر آپ داعی الی اللہ بنیں گے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہر گھر میں
انشاء اللہ ایک انقلاب پیدا ہونا شروع ہو جائے گا.اللہ تعالیٰ ہر داعی الی اللہ کو میٹھے پھل عطا
فرمائے گا اس لئے صبر کریں اور دعائیں کریں اور خدا کی راہ میں دکھ اٹھانے کے باوجود راضی
رہیں اور اپنی شکائتیں لوگوں سے نہ کریں بلکہ اللہ سے کریں وہ کافی ہے.نِعْمَ الْمَوْلى وَنِعْمَ
النَّصِيرُ اس سے بہتر کوئی اور مولیٰ نہیں ہے.اس کا سہارا آپ کو مل جائے تو کسی اور سہارے
کی آپ کو ضرورت نہیں ہے اور پھر وہ آپ کا بہترین وکیل ہے آپ کے سب جھگڑے وہ
اپنے فضل سے طے کروائے گا اور وہ سب سے زیادہ توکل کے لائق ذات ہے.خطبہ جمعہ حضرت خلیفہ امسح الرابع رحمہ اللہ فرموده 18 فروری 1983 ء.خطبات طاہر جلد 2 صفحہ 87 -%105)
(
حضرت
خلیفہ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز فرماتے ہیں:
حمد اپنی حالتوں کو درست کرنے کے بعد، اپنی عبادتوں کے معیار بلند کرنے کے بعد، اپنی
مسجدوں کو پیارو محبت کا نشان بنانے کے بعد ، جس سے اللہ تعالیٰ کی توحید کے پیغام کے ساتھ
پیار ومحبت کا پیغام ہر طرف پھیلانے کا نعرہ بلند ہو، احمدیت یعنی حقیقی اسلام کے پیغام کو اپنے
علاقے کے ہر
شخص تک پہنچادیں.یہی پیغام ہے جو اللہ تعالیٰ کی پسند ہے.اور یہی پیغام ہے
جس سے دنیا کا امن اور سکون وابستہ ہے.یہی پیغام ہے جس سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہونا
ہے.آج روئے زمین پر اس خوبصورت پیغام کے علاوہ کوئی پیغام نہیں جو دنیا کو امن اور
محبت کا گہوارہ بنا سکے اور بندے کو خدا کے حضور جھکنے والا بنا سکے.اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں
فرماتا ہے کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَ قَالَ إِنَّنِي مِنَ
598
Page 607
الْمُسْلِمِينَ (حم السجدہ (34).یعنی اس سے زیادہ اچھی بات کس کی ہوگی جو کہ اللہ کی طرف
لوگوں کو بلاتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے اور کہے کہ میں یقینا کامل فرمانبرداروں میں سے ہوں.پس یہ کامل فرمانبرداری جس کی ہر احمدی سے توقع کی جاتی ہے اس وقت ہوگی جب نیک،
صالح عمل ہورہے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی ہورہی ہوگی.اللہ تعالیٰ کے بندوں کے
حقوق بھی ادا ہور ہے ہوں گے.اور پھر ایسے لوگ جب دعوت الی اللہ کرتے ہیں تو ان کی سچائی
کی وجہ سے لوگ بھی ان کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں.اور ان نیک کاموں کی وجہ سے ایسے
لوگ اللہ تعالیٰ کے بھی منظور نظر ہو جاتے ہیں.اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی مدد بھی فرماتا ہے.تبلیغی میدان میں ان کی روکیں دور ہو جاتی ہیں.وہی مخالفین جو مساجد کی تعمیر میں روکیں ڈال
رہے ہوتے ہیں وہی جو مسلمانوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، وہی جو برداشت نہیں کر
سکتے کہ ان کے علاقے میں مسلمان عبادت کی غرض سے جمع ہوں جب آپ کے عمل دیکھیں
گے، آپ کی عبادتیں دیکھیں گے، آپ کی پیشانیوں پر ان لوگوں کو نشان نظر آئیں گے جن
سے مومن کی پہچان ہوتی ہے...بہر حال اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے والوں اور عمل صالح کرنے
والوں سے پھر اللہ تعالیٰ یہ وعدہ فرماتا ہے کہ تم ایسے کام کرو گے اور تم اپنا ہر فعل خدا کی خاطر کرو
گے اور کامل فرمانبردار بن جاؤ گے تو پھر تمہاری ان کوششوں کو اللہ تعالیٰ اس طرح پھل
لگائے گا کہ جو تمہارے دشمن ہیں وہ بھی تمہارے دوست بن جائیں گے.جیسا کہ فرماتا ہے.ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِى حَمِيمٌ
( حم السجد 358) کہ ایسی چیز سے دفاع کر جو بہترین ہو.تب ایسا شخص جس کے اور تیرے
در میان دشمنی تھی وہ گویا اچانک ایک جاں نثار دوست بن جائے گا.پس بہترین دفاع اسلام کی
خوبصورت تعلیم سے، اور اس تعلیم کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنانے سے ہوگا.یہ سب الزامات جو
آج اسلام پر لگائے جاتے ہیں اُن کو عملی نمونے کے ساتھ دھونے کے لئے ، اس پیغام کو
پہنچانا بہت ضروری ہے.599
Page 608
پس حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ تعلیم اس لئے تھی کہ اگر دشمن بھی ہو تو
اس نرمی اور حسن سلوک سے دوست بن جائے اور ان باتوں کو آرام اور سکون کے ساتھ سمجھ لے.پھر آپ فرماتے ہیں : ” تقویٰ کے بہت سے اجزاء ہیں.تُحجب ،خود پسندی، مال حرام
سے پر ہیز اور بداخلاقی سے بچنا بھی تقویٰ ہے.جو شخص اچھے اخلاق ظاہر کرتا ہے اس کے دشمن
بھی دوست ہو جاتے ہیں“.پھر فرمایا: ”اب خیال کرو کہ یہ ہدایت کیا تعلیم دیتی ہے؟.اس ہدایت میں اللہ تعالیٰ
کا یہ منشاء ہے کہ اگر مخالف گالی بھی دے تو اس کا جواب گالی سے نہ دیا جائے بلکہ اس پر صبر کیا
جائے.یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کے بارے میں ہے.اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مخالف
تمہاری فضیلت کا قائل ہو کر خود ہی نادم اور شرمندہ ہوگا.اور یہ سزا اس سزا سے بہت بڑھ کر ہو
گی جو انتقامی طور پر تم اس کو دے سکتے ہو.یوں تو ایک ذرا سا آدمی اقدام قتل تک نوبت پہنچا
سکتا ہے لیکن انسانیت کا تقاضا اور تقویٰ کا منشاء یہ نہیں ہے.خوش اخلاقی ایک ایسا جوہر ہے کہ
موزی سے موذی انسان پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے.“
( ملفوظات جلد اول صفحہ 68-69 ایڈیشن 2003ء مطبوعہ ربوہ )
پس یہ اعمال صالحہ کا معیار ہے جو ہم نے اپنا نا ہے.اور اس سے تبلیغی راستے بھی کھلیں
گے.اور اس سے ہماری آپس کی رنجشیں اور کدورتیں بھی دور ہوں گی.کیونکہ نیک نمونے
دکھانے کے لئے ، احمدی معاشرے کا وقار قائم کرنے کے لئے آپس میں بھی محبت پیار سے
رہتے ہوئے رنجشیں دور کرنے کی کوشش کرنی ہوگی.( خطبہ جمعہ حضرت خلیفتہ است خلیفة اسم الخامس اید والله فرمود 18 رجون 2006ء - خطبات مسر درجلد چہارم صفحه 29-299)
اسی طرح حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے خطبہ جمعہ فرمودہ 30
ستمبر 2005ء میں سورۃ حم السجدہ کی آیت 34 کی تلاوت اور ترجمہ کے بعد فرمایا:
اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ تم لوگ جو ایمان
لے آئے ہو اور دین کی کچھ شدھ بدھ رکھتے ہو اور یہ دعویٰ کرتے ہو کہ مسلمان ہو گئے ہوا گر تم
600
Page 609
حقیقت میں مسلمان ہو اور نام کے مسلمان نہیں بلکہ کامل فرمانبرداری اور اطاعت کا جذ بہ رکھتے
ہوئے تم نے اسلام قبول کیا ہے تو یاد رکھو کہ تم پر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں.اور ان میں
سے ایک ذمہ داری تبلیغ دین بھی ہے.اور تبلیغ بھی اس وقت فائدہ مند ہوگی ، اس وقت اس کو
بھی پھل لگیں گے جب تمہارے عمل بھی نیک ہوں گے.پس ایک احمدی جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے اس زمانے کے حکم اور عدل حضرت مسیح
موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اس لئے مانا ہے کہ میں کامل فرمانبرداروں میں شمار کیا جاؤں، اس
لئے مانا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کروں، اس لئے مانا ہے کہ آج خدا
تک پہنچنے کا راستہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی دکھایا ہے تو پھر ہر وقت یہ بات
ذہن میں رکھنی چاہئے کہ تمام فیض بھی تبھی حاصل کر سکتے ہیں جب ان تمام حکموں پر بھی عمل کریں
گے جو اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے اور جن کی طرف اس زمانے میں ہمیں
حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے توجہ دلائی.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی
نے فرمایا تھا کہ میرا پیغام تمام دنیا کو پہنچا دو اور آپ کو سب سے بڑا داعی الی اللہ قرار دیا
تھا.فرماتا ہے دَاعِيًّا إِلَى اللهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا منيرا ( الاحزاب 47) یعنی اور اللہ کے حکم
سے اس کی طرف بلانے والا اور ایک چمکتا ہوا سورج بنا کر بھیجا ہے.پس اس چمکتے ہوئے
سورج نے ہر طرف اللہ تعالیٰ کی تعلیم کی روشنی پھیلائی اور اپنا سب کچھ اس راہ میں قربان کر دیا.اور اندھیروں کو دور کیا.جہاں آپ نے دعوت الی اللہ کر کے خودان اندھیروں کو دور کیا وہاں
اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مَن دَعَا إِلَى اللهِ (حم السجدہ 34 ) اپنے
ماننے والوں کو بھی یہ نصیحت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو آگے پہنچاتے رہو.اور تم دنیا میں
جو بھی بات کرتے ہو ان میں سب سے زیادہ پیاری اور خوبصورت وہ باتیں ہوتی ہیں جب تم اللہ
تعالی کا پیغام دوسروں تک پہنچارہے ہوتے ہو لیکن ساتھ یہ بات بھی ہر وقت ذہن نشین رکھنی
601
Page 610
چاہئے کہ دعوت الی اللہ اور تبلیغ بھی اس وقت ہی اللہ کے نزدیک اور اس کے رسول کے
نزد یک نیکی شمار ہو گی جب تمہارے عمل بھی نیک ہوں گے.ور نہ تو گنہگار ہو گے.ایسی تبلیغ
میں برکت ہی نہیں ہوگی جب اپنے عمل اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق نہ ہوں.خطبہ جمعہ حضرت خلیفتہ امسح الخامس اید والله، فرمودہ 30 ستمبر 2005ء.خطبات مسرور جلد سوم صفحہ 587-588)
602
Page 611
سورة الحشر آيات 19 تا 25
يَايُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرُ 19.اے مومنو! اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور چاہیے کہ
ہر جان اس بات پر نظر رکھے کہ اس نے کل کے لئے
نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا الله
آگے کیا بھیجا ہے اور تم سب اللہ کا تقویٰ اختیار کرو.إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ
اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے.وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِيْنَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسُهُمْ 20.اور ان لوگوں کی طرح نہ بنو جنہوں نے اللہ کو
أَنْفُسَهُمْ أُولَبِكَ هُمُ الْفَسِقُونَ ) بھلا دیا سو اللہ نے بھی ان کو اپنی جانوں کا فائدہ بھلا
دیا یہ لوگ اطاعت سے باہر نکلنے والے ہیں.لَا يَسْتَوِي اَصْحَبُ النَّارِ وَاَصْحَبُ الْجَنَّةِ 21.دوزخی اور جنتی برابر نہیں ہو سکتے.جنتی
لوگ ہی کامیاب ہیں.اصْحَبُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَابِزُونَ
لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ أَرَأَيْتَهُ 22.اگر یہ قرآن ہم کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تُو
اسے دیکھتا کہ وہ ( ادب سے ) جھک جاتا اور اللہ
کے ڈرسے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا.اور یہ باتیں جو ہم
( تجھ سے ) کہتے ہیں یہ سب انسانوں کے لئے ہیں
خَاشِعًا مُّتَصَدِّعَا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ
الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ
يَتَفَكَّرُونَ
تا کہ وہ سوچیں.هُوَ اللهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلِمُ الْغَيْبِ 23.اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں.وہ
وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ
غائب اور حاضر کو جانتا ہے وہی بے انتہا کرم کرنے
والا (خدا) ہے (اور وہی) بار بار رحم کرنے والا
(خدا) ہے.هُوَ اللهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ 24 (.حق یہ ہے کہ ) اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی
الْقُدُّوسُ السَّلَمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ
معبود نہیں.وہ بادشاہ ہے.(خود) پاک ہے
اور دوسروں کو پاک کرتا ہے.خود ) ہر عیب سے
603
Page 612
الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحْنَ اللَّهِ سلامت ہے ( اور دوسروں کو سلامت رکھتا ہے )
عَمَّا يُشْرِكُونَ
سب کو امن دینے والا ہے.اور سب کا نگران
ہے.غالب ہے.اور سب ٹوٹے ہوئے دلوں کو
جوڑتا ہے.بڑی شان والا ہے.جن چیزوں کو یہ
لوگ اس کا شریک قرار دیتے ہیں اُن سے اللہ
پاک ہے.هُوَ اللهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ 25(.حق یہی ہے کہ ) اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا
لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا
اور ہر چیز کا موجد بھی ہے.اور ہر چیز کو اس کی
مناسب حال صورت دینے والا ہے.اس کی بہت
فِي السَّمَوتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَهُوَ سی اچھی صفات ہیں.آسمانوں اور زمین میں جو کچھ
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُن
ہے اس کی تسبیح کر رہا ہے.اور وہ غالب ( اور )
حکمت والا ہے.604
Page 613
حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں:
اے ایمان والو خدا سے ڈرتے رہو اور ہر ایک تم میں سے دیکھتا ر ہے کہ میں نے اگلے
جہان میں کون سا مال بھیجا ہے اور اس خدا سے ڈرو جو خبیر اور علیم ہے اور تمہارے اعمال دیکھ رہا
ہے یعنی وہ خوب جاننے والا اور پر کھنے والا ہے اس لئے وہ تمہارے کھوٹے اعمال ہر گز قبول
نہیں کرے گا.ست بچن، روحانی خزائن جلد 10 صفحہ 225 ، 226)
یہ قرآن جو تم پر اُتارا گیا اگر کسی پہاڑ پر اُتارا جاتا تو وہ خشوع اور خوف الہی سے ٹکڑہ ٹکڑہ
ہو جا تا اور یہ مثالیں ہم اس لیے بیان کرتے ہیں تا لوگ کلام الہی کی عظمت معلوم کرنے کے
لئے غور اور فکر کریں.سرمه چشم آریہ، روحانی خزائن جلد 2 صفحہ 63)
ایک تو اس کے یہ معنے ہیں کہ قرآن شریف کی ایسی تاثیر ہے کہ اگر پہاڑ پر وہ اترتا تو
پہاڑ خوفِ خدا سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا اور زمین کے ساتھ مل جاتا.جب جمادات پر اس کی ایسی
تا ثیر ہے تو بڑے ہی بے وقوف وہ لوگ ہیں جو اس کی تاثیر سے فائدہ نہیں اٹھاتے.اور دوسرے اس کے معنی یہ ہیں کہ کوئی شخص محبت الہی اور رضائے الہی کو حاصل نہیں کر سکتا
جب تک دو صفتیں اس میں پیدا نہ ہو جائیں.اول تکبر کو توڑ نا جس طرح کہ کھڑا ہوا پہاڑ جس نے
سر اونچا کیا ہوا ہوتا ہے گر کر زمین سے ہموار ہو جائے.اسی طرح انسان کو چاہیے کہ تمام تکبر اور
بڑائی کے خیالات کوڈ ور کرے.عاجزی اور خاکساری کو اختیار کرے.اور دوسرا یہ ہے کہ پہلے تمام تعلقات اس کے ٹوٹ جائیں جیسا کہ پہاڑ کر کر مُتَصَدِّعًا ہو
جاتا ہے.اینٹ سے اینٹ جدا ہو جاتی ہے.ایسا ہی اس کے پہلے تعلقات جو موجب گندگی اور
605
Page 614
الہی نارضامندی کے تھے وہ سب تعلقات ٹوٹ جائیں اور اب اس کی ملاقاتیں اور دوستیاں اور
محبتیں اور عداوتیں صرف اللہ تعالیٰ کے لئے رہ جائیں.الحکم جلد 5 نمبر 21 مورخہ 10 / جون 1901 صفحہ 9)
وہ خدا جو واحد لاشریک ہے جس کے سوا کوئی بھی پرستش اور فرمانبرداری کے لائق
نہیں.یہ اس لئے فرمایا کہ اگر وہ لاشریک نہ ہو تو شاید اس کی طاقت پر دشمن کی طاقت غالب
آ جائے.اس صورت میں خدائی معرض خطرہ میں رہے گی.اور یہ جو فرمایا کہ اس کے سوا کوئی پرستش کے لائق نہیں.اس سے یہ مطلب ہے کہ وہ ایسا
کامل خدا ہے جس کی صفات اور خوبیاں اور کمالات ایسے اعلیٰ اور بلند ہیں کہ اگر موجودات میں
سے بوجہ صفات کاملہ کے ایک خدا انتخاب کرنا چاہیں یا دل میں عمدہ سے عمدہ اور اعلی سے اعلیٰ خدا
کی صفات فرض کریں تو سب سے اعلیٰ جس سے بڑھ کر کوئی اعلیٰ نہیں ہوسکتا.وہی خدا ہے جس
کی پرستش میں ادنی کو شریک کرنا ظلم ہے.پھر فرمایا کہ عالم الغیب ہے یعنی اپنی ذات کو آپ ہی جانتا ہے.اس کی ذات پر کوئی
احاطہ نہیں کرسکتا.ہم آفتاب اور ماہتاب اور ہر ایک مخلوق کا سراپا د یکھ سکتے ہیں مگر خدا کا سراپا
دیکھنے سے قاصر ہیں.پھر فرمایا کہ وہ عالم الشہادۃ ہے.یعنی کوئی چیز اس کی نظر سے پردہ میں نہیں ہے.یہ جائز
نہیں کہ وہ خدا کہلا کر پھر علم اشیاء سے غافل ہو.وہ اس عالم کے ذرہ ذرہ پر اپنی نظر رکھتا ہے
لیکن انسان نہیں رکھ سکتا.وہ جانتا ہے کہ کب اس نظام کو توڑ دے گا اور قیامت برپا کر دے گا.اور اس کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ ایسا کب ہوگا؟ سو وہی خدا ہے جو ان تمام وقتوں کو جانتا ہے.پھر فرما یا هو الرحمن یعنی وہ جانداروں کی ہستی اور ان کے اعمال سے پہلے محض اپنے لطف
سے، نہ کسی غرض سے اور نہ کسی عمل کی پاداش میں ان کے لئے سامان راحت میسر کرتا ہے.جیسا کہ آفتاب اور زمین اور دوسری تمام چیزوں کو ہمارے وجود اور ہمارے اعمال کے وجود سے
پہلے ہمارے لئے بنا دیا.اس عطیہ کا نام خدا کی کتاب میں رحمانیت ہے.اور اس کام کے لحاظ
606
Page 615
سے خدائے تعالیٰ رحمن کہلاتا ہے.اور پھر فرمایا کہ الرّحیم یعنی وہ خدا نیک عملوں کی نیک تر
جزا دیتا ہے اور کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا اور اس کام کے لحاظ سے رحیم کہلاتا ہے.اسلامی اصول کی فلاسفی ، روحانی خزائن جلد 10 صفحہ 374،373)
هُوَ اللهُ الَّذِى لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَمُ الْمُؤْمِنُ
الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَيْرُ سُبْحَنَ اللهِ عَمَّا يُغرِكُونَ.الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ یعنی وہ خدا بادشاہ ہے جس پر کوئی داغ عیب نہیں.یہ ظاہر ہے کہ
انسانی بادشاہت عیب سے خالی نہیں.اگر مثلاً تمام رعیت جلا وطن ہو کر دوسرے ملک کی طرف
بھاگ جاوے تو پھر بادشاہی قائم نہیں رہ سکتی یا اگر مثلاً تمام رعیت قحط زدہ ہو جائے تو پھر خراج
شاہی کہاں سے آئے اور اگر رعیت کے لوگ اس سے بحث شروع کر دیں کہ تجھ میں ہم سے
زیادہ کیا ہے تو وہ کون سی لیاقت اپنی ثابت کرے.پس خدا تعالیٰ کی بادشاہی ایسی نہیں ہے.وہ ایک دم میں تمام ملک کو فنا کر کے اور مخلوقات پیدا کر سکتا ہے.اگر وہ ایسا خالق اور قادر نہ
ہوتا تو پھر بجر ظلم کے اس کی بادشاہت چل نہ سکتی.کیونکہ وہ دنیا کو ایک مرتبہ معافی اور نجات
دے کر پھر دوسری دنیا کہاں سے لاتا.کیا نجات یافتہ لوگوں کو دنیا میں بھیجنے کے لئے پھر پکڑتا
اور ظلم کی راہ سے اپنی معافی اور نجات دہی کو واپس لیتا ؟ تو اس صورت میں اس کی خدائی میں
فرق آتا اور دنیا کے بادشاہوں کی طرح داغدار بادشاہ ہوتا جو دنیا کے لئے قانون بناتے ہیں.بات بات میں بگڑتے ہیں.اور اپنی خود غرضی کے وقتوں پر جب دیکھتے ہیں کہ ظلم کے بغیر چارہ
نہیں توظلم کو شیر مادر سمجھ لیتے ہیں.مثلاً قانون شاہی جائز رکھتا ہے کہ ایک جہاز کو بچانے کے
لئے ایک کشتی کے سواروں کو تباہی میں ڈال دیا جائے اور ہلاک کیا جائے مگر خدا کو تو یہ اضطرار
پیش نہیں آنا چاہئے.پس اگر خدا پورا قادر اور عدم سے پیدا کرنے والا نہ ہوتا تو یا تو وہ کمزور
راجوں کی طرح قدرت کی جگہ ظلم سے کام لیتا اور یا عادل بن کر خدائی کو ہی الوادع کہتا.بلکہ خدا
کا جہا ز تمام قدرتوں کے ساتھ سچے انصاف پر چل رہا ہے.607
Page 616
پھر فرمایا السّلام یعنی وہ خدا جو تمام عیبوں اور مصائب اور سختیوں سے محفوظ ہے بلکہ
سلامتی دینے والا ہے.اس کے معنے بھی ظاہر ہیں کیونکہ اگر وہ آپ ہی مصیبتوں میں پڑتا لوگوں
کے ہاتھ سے مارا جاتا اور اپنے ارادوں میں ناکام رہتا تو پھر اس بدنمونہ کو دیکھ کر کس طرح دل
تسلی پکڑتے کہ ایسا خدا ہمیں ضرور مصیبتوں سے چھڑا دے گا...اور پھر فرمایا کہ خدا امن کا بخشنے
والا اور اپنے کمالات اور توحید پر دلائل قائم کرنے والا ہے.یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ
سچے خدا کا ماننے والا کسی مجلس میں شرمندہ نہیں ہوسکتا اور نہ خدا کے سامنے شرمندہ ہوگا کیونکہ اس
کے پاس زبردست دلائل ہوتے ہیں.لیکن بناوٹی خدا کا ماننے والا بڑی مصیبت میں ہوتا
ہے.وہ بجائے دلائل بیان کرنے کے ہر ایک بیہودہ بات کو راز میں داخل کرتا ہے تا ہنسی نہ
ہو اور ثابت شدہ غلطیوں کو چھپانا چاہتا ہے.اور پھر فرمایا کہ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَگیر یعنی وہ سب کا محافظ ہے اور سب
پر غالب اور بگڑے ہوئے کاموں کا بنانے والا ہے.اور اس کی ذات نہایت ہی مستغنی ہے.اسلامی اصول کی فلاسفی ، روحانی خزائن جلد 10 صفحہ 374،373)
هُوَ اللهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوَّرُ لَهُ الْأَسْمَاء الْحُسْنِى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي
السَّمَوتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
یعنی وہ ایسا خدا ہے کہ جسموں کا بھی پیدا کرنے والا اور روحوں کا بھی پیدا کرنے والا.رحم میں تصویر کھینچنے والا ہے.تمام نیک نام جہاں تک خیال میں آسکیں سب اُسی کے نام ہیں.اور پھر فرما یا يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.یعنی آسمان کے
لوگ بھی اس کے نام کو پاکی سے یاد کرتے ہیں اور زمین کے لوگ بھی.اس آیت میں اشارہ
فرمایا کہ آسمانی اجرام میں آبادی ہے اور وہ لوگ بھی پابند خدا کی ہدایتوں کے ہیں.اسلامی اصول کی فلاسفی ، روحانی خزائن جلد 10 صفحه 375)
608
Page 617
حضرت خلیفہ المسیح الاول رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں :
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ.وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ مَا تَعْمَلُونَ.اے ایمان والو! اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور ہر نفس کو چاہئے کہ دیکھتا رہے کہ کل کے
لئے اس نے کیا کیا اور تقویٰ اپنا شعار بنائے.اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے خوب آگاہ
ہے.غرض دنیا و عقبی میں کامیابی کا ایک گر بتایا کہ انسان کل کی فکر آج کرے اور اپنے ہر قول و
فعل میں یہ یادر کھے کہ خدا تعالیٰ میرے کاموں سے خبردار ہے.یہی تقویٰ کی جڑھ ہے.اور
یہی ہر ایک کامیابی کی رُوح رواں ہے.برخلاف اس کے انجیل کی یہ تعلیم ہے جو ( متی ) باب
6 آیت 33 میں مذکور ہے بایں الفاظ کہ کل کے لئے فکر نہ کروکیونکہ کل کا دن اپنے لئے آپ
فکر کرے گا.آج کا دُکھ آج کے لئے کافی ہے.اگر ان دونوں تعلیموں پر غور کریں تو صرف اسی ایک مسئلہ سے اسلام و عیسائیت کی صداقت
کا فیصلہ ہوسکتا ہے.اور ایک نیک دل پارسا طالب نجات، طالب حق خوب
سمجھ لیتا ہے کہ عملی
زندگی کے اعتبار سے کون سا مذہب احق بالقبول ہے.اگر انجیل کی اس آیت پر ہم کیا، خود انجیل کے ماننے والے عیسائی بھی عمل کریں تو دنیا کی
تمام ترقیاں رُک جائیں اور تمام کاروبار بند ہو جائیں.نہ تو بجٹ بنیں.نہ ان کے مطابق
عمل درآمد ہو.نہ ریل گاڑیوں اور جہازوں کے پروگرام پہلے شائع ہوں.نہ کسی تجارتی
کارخانے کو اشتہار دینے کا موقعہ ملے.نہ کسی گھر میں کھانے کی کوئی چیز پائی جائے.اور نہ غالباً
بازاروں سے مل سکے.کیونکہ کل کی تو فکر ہی نہیں.بلکہ فکر کرنا ہی گناہ ہے.برخلاف اس کے
قرآن مجید کی تعلیم کیا پاک اور عملی زندگی میں کام آنے والی ہے.اور لطف یہ ہے کہ عیسائیوں کا
اپنا عمل درآمد بھی اسی آیت پر ہے.ورنہ آج ہی سے سب کا روبار عالم بند ہوجائیں.اور کوئی
نظام سلطنت قائم نہ رہے.قرآن پاک کی تعلیم وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ پر عمل کرنے
609
Page 618
سے انسان نہ صرف دُنیا میں کامران ہوتا ہے بلکہ حقمی میں بھی خدا کے فضل سے سرخرو ہو گا.ہم
کبھی آخرت کے لئے سرمایہ نجات جمع نہیں کر سکتے جب تک آج ہی سے اس دار القرار کے
لئے تیاری نہ شروع کر دیں.تشخيذ الاذبان جلد 7 نمبر 5 مئی 1912 ، صفحہ 227 228)
چاہئے کہ ہر ایک نفس دیکھ لے کہ اس نے کل کے واسطے کیا تیاری کی ہے.انسان
کے ساتھ ایک نفس لگا ہوا ہے جو ہر وقت مبدل ہے.کیونکہ جسم انسانی ہر وقت تحلیل ہو رہا
ہے.جب اس نفس کے واسطے جو ہر وقت تحلیل ہو رہا ہے اور اس کے ذرات جُدا ہوتے
جاتے ہیں اس قدر تیاریاں کی جاتی ہیں اور اس حفاظت کے واسطے سامان مہیا کئے جاتے
ہیں.تو پھر کس قدر تیاری اس نفس کے واسطے ہونی چاہئے جس کے ذمہ موت کے بعد کی
جواب دہی لازم ہے.اس آنی فنا والے جسم کے واسطے جتنا فکر کیا جاتا ہے.کاش کہ اتنا فکر
اس کے نفس کے واسطے کیا جاوے جو کہ جواب دہی کرنے والا ہے.إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ.اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے آگاہ ہے.اس آگاہی کا لحاظ
کرنے سے آخر کسی نہ کسی وقت فطرتِ انسانی جاگ کر اسے ملامت کرتی ہے اور گناہوں میں
گرنے سے بچاتی ہے.( بدر جلد 2 نمبر 50 مورخہ 13 دسمبر 1906 ، صفحہ 9)
مومن کو چاہئے کہ جو کام کرے اس کے انجام کو پہلے سوچ لے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا ؟
انسان غضب کے وقت قتل کر دینا چاہتا ہے.گالی نکالتا ہے.مگر وہ سوچے کہ اس کا انجام کیا ہو
گا؟ اس اصل کو مد نظر رکھے تو تقویٰ کے طریق پر قدم مارنے کی توفیق ملے گی.نتائج کا خیال
کیونکر پیدا ہو.اس لئے اس بات پر ایمان رکھے کہ وَاللهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ جو کام تم کرتے
ہواللہ تعالیٰ کو اس کی خبر ہے.انسان اگر یہ یقین کرلے کہ کوئی خبیر وعظیم بادشاہ ہے جو ہر قسم کی
بدکاری، دغا، فریب، سُستی اور کاہلی کو دیکھتا ہے اور اس کا بدلہ دے گا تو وہ بچ سکتا ہے.ایسا
ایمان پیدا کرو.بہت سے لوگ ہیں جو اپنے فرائض نوکری ، حرفہ، مزدوری وغیرہ میں سستی
610
Page 619
کرتے ہیں.ایسا کرنے سے رزق حلال نہیں رہتا.اللہ تعالیٰ سب کو تقویٰ کی توفیق دے.الحکم نمبر 19، 20 جلد 15 مورخہ 21، 28 مئی 1911 ، صفحہ 26)
وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللهَ فَأَنْسَهُمْ أَنْفُسَهُمْ - أُولَئِكَ هُمُ
الْفَاسِقُونَ
ایسے لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جن کی نسبت فرمایا - نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ.یعنی جنہوں نے اس رحمت اور پاکی کے سرچشمہ قدوس خدا کو چھوڑ دیا اور اپنی شرارتوں ،
چالاکیوں ، ناعاقبت اندیشیوں، غرض قسم قسم کی حیلہ سازیوں اور رو بہ بازیوں سے کامیاب ہونا
چاہتے ہیں.مشکلات انسان پر آتی ہیں.بہت سی ضرورتیں انسان کو لاحق ہیں.کھانے پینے کا
محتاج ہوتا ہے.دوست بھی ہوتے ہیں.دشمن بھی ہوتے ہیں.مگر ان تمام حالتوں میں منتقی کی یہ
شان ہوتی ہے کہ وہ خیال اور لحاظ رکھتا ہے کہ خدا سے بگاڑ نہ ہو.دوست پر بھروسہ ہو ممکن ہے
کہ وہ دوست مصیبت سے پیشتر دنیا سے اُٹھ جاوے یا اور مشکلات میں پھنس کر اس قابل نہ
رہے.حاکم پر بھروسہ ہوتو ممکن ہے کہ حاکم کی تبدیلی ہو جاوے اور وہ فائدہ اس سے نہ پہنچ سکے.اور اُن احباب اور رشتہ داروں کو جن سے امید اور کامل بھروسہ ہو کہ وہ رنج اور تکلیف میں امداد
دیں گے.اللہ تعالیٰ اس ضرورت کے وقت ان کو اس قدر ڈ ورڈال دے کہ وہ کام نہ آسکیں.پس ہر آن خدا سے تعلق نہ چھوڑنا چاہئے جو زندگی موت کسی حالت میں ہم سے جدا نہیں ہوسکتا.پس خدا تعالی فرماتا ہے کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے خدا سے قطع تعلق کر لیا
ہے.اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم دُکھوں سے محفوظ نہ رہ سکو گے اور سکھ نہ پاؤ گے بلکہ ہر طرف سے
ذلت کی مار ہوگی اور ممکن ہے کہ وہ ذلت تم کو دوستوں ہی کی طرف سے آ جاوے.ایسے لوگ
جو خدا سے قطع تعلق کرتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ فاسق فاجر ہوتے ہیں.اُن میں سچا
اخلاص اور ایمان نہیں ہوتا.یہی نہیں کہ وہ ایمان کے کچے ہیں.نہیں، ان میں شفقت
علی خلق اللہ بھی نہیں ہوتی.الحکم نمبر 5 جلد 3 مورخہ 10 فروری 1899 صفحہ 8-9)
611
Page 620
اسلام کا اصلی سر چشمہ اور اس کا حقیقی منبع اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے جس کا نام
السّلام ہے.قرآن کریم میں اس مبارک نام کا مبارک ذکر اس کلمہ طیبہ میں آیا ہے.هُوَ الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام
یعنی وہی اللہ ہے.کوئی معبود اور کاملہ صفات سے موصوف اس کے سوا نہیں.وہ حقیقی
بادشاہ ہر ایک نقص سے منزہ ہ بے عیب و سلامت ہے.اور اسلام کا حقیقی ثمرہ دارالسلام ہے.جس کا آسمان و زمین اور درو دیوار اور اس کے تمام یار و غمگسار طیب ہوں گے.اور ان کے
میل جول میں سلامتی و سلام ہی ہوگا.جیسے فرمایا.وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَمُ (يونس (11)
(ماخوذ از حقائق الفرقان)
حضرت خلیفہ المسیح الثانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:
قرآن کریم میں خدا تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم یہ دیکھو تم نے کل کے لئے سامان کیا
ہے یا نہیں بلکہ یہ فرمایا کہ یہ دیکھوکل کے لئے کیا سامان کیا.کل کے لئے کچھ نہ کچھ سامان
کرنا تو فطرتی بات ہے جو حیوانوں میں بھی پائی جاتی ہے.کیڑے مکوڑوں میں بھی پائی جاتی
ہے.چیونٹی اور شہد کی مکھی خوراک جمع کر لیتی ہے.اور بھی جاندار ہیں جو آئندہ کے لئے
اندوختہ رکھتے ہیں.اس صورت میں انسان سے یہ سوال کہ اس نے آئندہ کے لئے جمع کیا ہے
یا نہیں؟ ایسا موٹا اور اتنا معمولی سوال ہے جو مذہب سے تعلق نہیں رکھتا.یہ بات تو
حیوانوں میں بھی پائی جاتی ہے.بلکہ سوال یہ ہے کہ کیا جمع کرتے ہو اور کہاں جمع کرتے ہو؟
حضرت مسیح ناصری علیہ السلام نے کیا عمدہ بات فرمائی کہ اپنا مال وہاں جمع کرو جہاں چوری کا
طرہ نہیں.یہی مطلب ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ کا کہ دیکھو تم نے کل کے لئے کیا
جمع کیا اور کہاں جمع کیا.اگر تم نے اچھی جگہ کوئی چیز جمع کرائی تو وہ چیز بھی اچھی ہو گی.اس
لئے اصل سوال یہی ہے کہ کہاں جمع کرائی.وہ چیز جس کے لئے کوئی خطرہ نہیں وہی ہو سکتی
ہے جسے خدا تعالیٰ کے ہاں جمع کرایا جائے.اور خدا تعالیٰ فرماتا ہے ہم انسان پر کوئی ظلم
612
Page 621
نہیں کرتے.انسان کوئی نیکی نہیں کرتا کہ ہم اس کا بدلہ بڑھا چڑھا کر نہیں دیتے.اس لئے
ضروری ہے کہ جب انسان کوئی اہم کام کرنے لگے تو ساتھ کوئی نہ کوئی نیکی بھی کرے.صلحاء اور
انبیاء کا یہی طریق ہے.( خطبات محمود جلد سوم صفحہ 324)
حضرت خلیفہ المسح الثالث نے سورۃ الحشر کی آیات 19 تا 21 کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا:
پہلی آیت میں یہ بنیادی ہدایت دی گئی ہے کہ تقویٰ اللہ کا تقاضا ہے کہ انسان اس بات
پر نظر رکھے کہ مستقبل کے لئے وہ کیا کر رہا ہے.اس میں شک نہیں کہ انسان کا ماضی سے گہرا
تعلق ہے اور ہم اسے چھوڑ نہیں سکتے.اس کا لحاظ رکھنا، اسے فراموش نہ ہونے دینا بھی ضروری
ہے لیکن ماضی سے زیادہ جو چیز انسان سے تعلق رکھتی ہے وہ حال کا زمانہ ہے یا وہ زمانہ ہے جو
لمحہ بہ لمحہ مستقبل سے حال میں تبدیل ہوتا چلا جاتا ہے.مستقبل کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس نے
کبھی آنا ہی نہ ہو اور وہ ہمیشہ مستقبل ہی رہے.جو چیز مستقبل سے حال میں بدلتی چلی جاتی ہے
جب تک وہ حال میں نہ بدلے ہم اسے مستقبل کہتے ہیں.مستقبل اپنی ذات میں دائمی حیثیت کا
حامل نہیں ہوتا.وہ نہ صرف یہ کہ حال میں تبدیل ہو کر رہتا ہے بلکہ لمحہ بہ لمحہ حال میں تبدیل ہو رہا
ہوتا ہے.اس لحاظ سے دیکھا جائے تو مستقبل ہمارے حال کی تعمیل کرنے والا ہے.اللہ تعالیٰ
نے اس آیت میں فرمایا یہ ہے کہ انسان کو تقویٰ اللہ پر قائم ہو کر مضبوطی سے ایسے مقام پر کھڑا
ہونا چاہیے کہ اسے یہ اطمینان حاصل ہو سکے کہ میرا مستقبل جو کچھ بھی ہے جیسے جیسے وہ حال میں
تبدیل ہوگا وہ میرے لئے دکھ کا نہیں سکھ کا موجب ہوگا.یہ تو اس زندگی کی کیفیت ہے جو ہم اس دنیا میں گزارتے ہیں.یہاں مستقبل لمحہ بہ لمحہ حال میں
تبدیل ہورہا ہوتا ہے اور ہمیں یہ تاکید کی گئی ہے کہ ہم دنیا میں اس طور پر زندگی گزاریں کہ
مستقبل حال میں تبدیل ہو کر ہمارے لئے تکلیف کا موجب نہ بنے لیکن ایک نہ ختم ہونے والا
زمانہ بھی ہے جو اس زندگی میں حال کی شکل اختیار نہیں کرتا اور وہ ہے اُخروی زندگی کا لامتناہی
613
Page 622
زمانہ.وہ بھی مستقبل ہی ہے یہ زندگی اُس زندگی کا مقابلہ نہیں کرسکتی کیونکہ وہ دائمی ہے.متقی
لوگ اس بات پر بھی نظر رکھتے ہیں کہ وہ اس زندگی میں اُس مستقبل کو سنوارنے کی کوشش
کرتے رہیں تا کہ جب وہ مرنے کے بعد اُس زندگی میں داخل ہوں
تو وہاں انہیں تکلیف نہیں
بلکہ راحت میسر آئے اور وہ زندگی اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق آرام سے گزرے.یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس طرح اور کس طریق پر ہم مستقبل کو سنوار سکتے ہیں؟ دوسری
آیت میں اس کا جواب دیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ مستقبل کو سنوارنے کا طریق یہ ہے کہ
اپنے اللہ کو یا درکھو.جو قو میں یا نسلیں اللہ کو یاد نہیں رکھتیں، اللہ تعالیٰ ایسے سامان کرتا ہے کہ وہ
اپنے نفسوں کو بھول جاتی ہیں یعنی اپنی اور اپنی نسلوں کی فلاح پر ان کی نظر نہیں رہتی.جہاں تک
خدا تعالیٰ کو بھولنے کا تعلق ہے یہ دو طرح پر ہوتا ہے.ایک بھولنا یہ ہے کہ ایسا شخص خدا تعالیٰ
کی عبادت نہ کر کے، اس سے اس کی پناہ نہ مانگ کر، اس کے قہر اور غضب سے نہ ڈر کر، اس
کی محبت اور اس کے پیار کی قدر نہ جان کر، اس کی صفات کا رنگ اپنے پر نہ چڑھا کر اس سے
یکسر غافل ہو جاتا ہے.ایک بھولنا خدا کو یہ ہے کہ اس نے جو احکام انسان کو اس کے اپنے
نفس کے متعلق ، دوسرے بنی نوع کے متعلق ، معاشرہ کے متعلق ، اقتصادیات کے متعلق ،
سیاست کے متعلق دیئے ہیں انہیں تو وہ نظر انداز کر دیتا ہے اور اپنی چلانے اور من مانی کرنے
لگتا ہے.خدا تعالیٰ کو بھولنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے تیسری آیت میں کیا ہے
اور بتایا ہے کہ ایسے لوگوں پر خدا کے غضب کی آگ بھڑکتی ہے.وہ اس دنیا میں بھی خسارہ میں
رہتے ہیں اور اگلے جہان میں بھی خسارہ ان کے لئے مقدر ہوتا ہے کیونکہ وہاں جہنم ان کا ٹھکانہ
ہوگی.برخلاف اس کے جولوگ تقویٰ اللہ پر قائم ہو کر خدا تعالیٰ کو ہمیشہ یادرکھتے ہیں، اُس کی
عبادت بجالاتے ہیں ، اس سے اس کی پناہ طلب کرنے میں سُست نہیں ہوتے ، اپنے آپ
کو اُس کی صفات کے رنگ میں رنگین کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے جملہ احکام
614
Page 623
بجالا کر دنیوی اور اُخروی فلاح کے لئے ہمیشہ کوشاں رہتے ہیں ان کے لئے اس دنیا کو بھی
جنت بنا دیا جاتا ہے اور آخرت میں بھی ان کے لئے جنت مقدر ہوتی ہے.خطبات ناصر جلد ششم صفحه 155 تا 157)
حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز فرماتے ہیں:
ياَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ
وَاتَّقُوالله إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ لِمَا تَعْمَلُونَ.وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ
فَانْسُهُمْ أَنْفُسَهُمْ أَوْلَئِكَ هُمُ الْفُسِقُونَ (سورة الحشر 19-20)
ان آیات کا ترجمہ ہے کہ : اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو! اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ہر جان
یہ نظر رکھے کہ وہ کل کے لئے کیا آگے بھیج رہی ہے.اور اللہ کا تقوی اختیار کرو.یقینا اللہ اس
سے جو تم کرتے ہو ہمیشہ باخبر رہتا ہے.اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا
تو اللہ نے انہیں خود اپنے آپ سے غافل کر دیا.یہی بدکردار لوگ ہیں ، فاسق لوگ ہیں.اللہ تعالیٰ نے ایک مومن کے لئے بنیادی شرط تقویٰ رکھی ہے.اس بارے میں قرآن کریم
میں بیشمار آیات ہیں جن میں تقویٰ اختیار کرو، تقویٰ پر قائم رہو کی تلقین مختلف حوالوں سے
اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، مختلف احکامات دیئے ہیں.اور ان احکامات پر عمل کرنے والوں کو
تقویٰ پر چلنے والا یا متقی کہا ہے.اور عمل نہ کرنے والوں کو اُن کے انجام سے خوف دلایا.تقویٰ کیا ہے؟ اس کی جو تعریف یا مختصر الفاظ میں خلاصہ جو قرآنِ کریم سے ہمیں ملتا ہے،
وہ یہ لیا جا سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی رضا کو ہر چیز پر مقدم رکھتے ہوئے ، خدا تعالیٰ کو واحد ویگانہ اور
سب طاقتوں کا منبع سمجھتے ہوئے اُس کے حقوق ادا کرنا اور خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لئے
اُس کی مخلوق کے حقوق بھی ادا کرنا ہے.حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ایک جگہ اس طرح بیان فرمایا ہے کہ :
” خدا تعالی کی امانتوں اور ایمانی عہدوں کی حتی الوسع رعایت کرنا اور سر سے پیر تک جتنے
615
Page 624
قومی اور اعضاء ہیں، جن میں ظاہری طور پر آنکھیں اور کان اور ہاتھ اور پیر اور دوسرے اعضاء
ور باطنی طور پر دل اور دوسری قوتیں اور اخلاق ہیں، ان کو جہاں تک طاقت ہو، ٹھیک
ٹھیک محل ضرورت پر استعمال کرنا اور نا جائز مواضع سے روکنا اور ان کے پوشیدہ حملوں سے متنبہ
رہنا اور اسی کے مقابل پر حقوق العباد کا بھی لحاظ رکھنا، یہ وہ طریق ہے کہ انسان کی تمام روحانی
خوبصورتی اس سے وابستہ ہے.“
( ضمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم روحانی خزائن جلد 21 صفحہ 209-210)
پس یہ وہ معیار ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بیان فرمایا اور اس کی
ہم سے توقع بھی کی.چند جمعے پہلے بھی میں نے امانتوں اور عہدوں کا حق ادا کرنے کی طرف
توجہ دلائی تھی کہ ان کی ادائیگی ایمان سے وابستہ ہے اور عہدیداروں کے حوالے سے باتیں
ہوئی تھیں.آج میں اس کی کچھ مزید بات کرتا ہوں.آج کے اس دور میں ایمان لانے والوں میں سے احمدی وہ خوش قسمت ہیں جن کو اس
باریکی سے خدا تعالیٰ سے تعلق کی طرف توجہ دلائی گئی.یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا
ہم پر احسان ہے کہ کھول کھول کر ان اعلیٰ مدارج کے راستے دکھاتے ہیں جن سے ایک مومن
خدا تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتا ہے.یقیناً ہر انسان کا معیار، نیکی کا معیار بھی، فراست کا معیار
بھی سمجھ کا معیار بھی علم کا معیار بھی مختلف ہوتا ہے، ہر ایک کا معیار ایک جیسا نہیں ہوسکتا.اس
لئے ہر ایک کو یہ حکم ہے کہ اپنی استعدادوں اور صلاحیتوں کی انتہا تک اللہ تعالیٰ سے کئے گئے
عہد اور اُس کی امانتوں کی ادائیگی کو پہنچاؤ.اگر کوشش کر کے ہر مومن یہ انتہا حاصل کرنے کی
طرف متوجہ رہے گا تو تقویٰ کی راہوں پر چلنے والا شمار ہوگا.ہاتھ، پیر، کان، آنکھ کا استعمال ہے تو
ان کے صحیح استعمال کا حکم ہے.جن باتوں کے کرنے سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، اُن سے رُکنا
فرض ہے.یہ ظاہری اعضاء صرف مخلوق کے حق کی ادائیگی کے لئے نہیں ہیں کہ ان سے مخلوق کا
حق ادا کرو، یا اگر حق ادا نہیں کرتے ، عدم ادائیگی ہے تو تم پوچھے جاؤ گے.بلکہ بہت سے ایسے
کام ہیں جن کا مخلوق سے براہ راست تعلق نہیں ہوتا اور اُن سے مخلوق کو کوئی نقصان یا فائدہ بھی
616
Page 625
نہیں پہنچ رہا ہوتا.اگر ہم گہری نظر سے دیکھیں تو جو بعض عمل انسان کرتا ہے انسان کی اپنی ذات
کو ہی اُس کا فائدہ اور نقصان پہنچ رہا ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اُس کے کرنے یا نہ کرنے کا
حکم دیا ہے.جن کے نہ کرنے کا حکم ہے اُن کو کر کے انسان
اللہ تعالی کی قائم کردہ حدوں کو پھلانگ
رہا ہوتا ہے اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے جو اپنے حق قائم کئے ہیں اُن کو توڑ رہا ہوتا ہے اور پھر جن کے
کرنے کا حکم ہے انہیں نہ کر کے اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے انسان باہر نکل رہا ہوتا ہے.پس انسان کسی بھی کام کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کر کے یا نہ کر کے خدا تعالی کی حدوں
کو توڑ کر تقویٰ سے دور ہٹتا چلا جاتا ہے اور جوں جوں تقویٰ سے دوری ہوتی ہے انسان شیطان
کی جھولی میں گرتا چلا جاتا ہے.اس لئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا
ہے کہ ایک مومن نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کام نہ کرے بلکہ شیطان جو چھپ کر
حملہ کرتا رہتا ہے ان حملوں سے بھی آگاہ رہے.ہر وقت اس کی نظر شیطان کے حملوں کی طرف
ہو کہ کہیں وہ اُس پر حملہ آور نہ ہو جائے اور پھر اس آگاہی کی وجہ سے شیطان کے پوشیدہ حملوں
سے اپنے آپ کو بچائے.شیطان کے حملے مختلف طریقوں سے ہوتے ہیں.اس زمانے کی ایجادات میں بھی بہت سی
ایسی ہیں جو خود انسان کو نقصان پہنچا رہی ہوتی ہیں.اُن کے اچھے مقاصد کی بجائے وہ ایسے
کاموں کے لئے استعمال ہو رہی ہوتی ہیں جہاں شیطان کے حملے کا خطرہ ہے یا شیطان کا حملہ ہو
رہا ہوتا ہے.عبادتوں سے دور لے جا رہی ہوتی ہیں.اخلاق پر برا اثر ڈال رہی ہوتی ہیں.بظاہر انسان سمجھتا ہے کہ یہ میرے ذاتی معاملات ہیں اور کسی کو کیا کہ میں جوا کھیلتا ہوں.یا
رات گئے تک انٹرنیٹ پر فلمیں دیکھتا ہوں اور ٹی وی دیکھتا ہوں یا اس قسم کے اور کام کرتا
ہوں.بہت سارے ایسے غلط کام انسان کرتا ہے اور اُس کے خیال میں کسی کو اُن سے غرض
نہیں ہونی چاہئے کیونکہ وہ کسی کو براہ راست نقصان نہیں پہنچا ر ہے.لیکن جو غلط کام ہے، جو
اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق نہیں ہے، اُس کی مرضی کے خلاف ہے، وہ اسے پھر اللہ تعالیٰ کی
عبادت سے بھی دُور لے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حق ادا کرنے سے بھی دُور لے جاتا ہے اور
617
Page 626
بندوں کے حق ادا کرنے سے بھی دور لے جاتا ہے.ان ملکوں میں شرابیں، جوا، انٹرنیٹ،
گندی اور لغو فلمیں ہیں، غلط دوستیاں ہیں.یہ جہاں گھروں کو اُجاڑ رہی ہوتی ہیں وہاں نوجوانوں
کو غلط راستے پر ڈال کر خدا تعالیٰ کی ذات پر ایمان سے بھی ہٹا کر معاشرے کا ناسور بنا رہی
ہوتی ہیں.وہ لوگ ایک مستقل بیماری بن رہے ہیں.پس خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے ہر عضو کا اور ہر سوچ کا اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق اور
بر محل استعمال
تمہیں تقویٰ میں بڑھائے گا اور اس کے خلاف عمل تمہیں شیطان کی گود میں پھینک
دے گا اور جو شیطان کی گود میں گرتا ہے وہ یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوتا ہے.ان آیات میں، جن کا ترجمہ بھی آپ نے سن لیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایمان لانے کے
بعد تقوی اختیار کرو.اے مومنو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو.یہ دنیا اور اس کی
رنگینیاں اور آسانیاں اور آسائشیں تمہارا سب کچھ نہ ہوں، بلکہ یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی
خاطر تم نے کیا عمل کئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کئے گئے عمل ہی ہیں جو اگلے جہان میں
کام آنے ہیں یا اگلے جہان میں کام آتے ہیں.دنیا کی تمام رنگینیاں اور مزے اور لذتیں اور
آسائشیں اسی دنیا میں رہ جاتی ہیں.پس اپنے جائزے لیتے رہو.کیونکہ گناہوں کی جڑ یہی ہے کہ انسان اپنے عملوں سے لا پرواہ
ہو جاتا ہے.خدا تعالیٰ کو بھول جاتا ہے.پس اگر اگلے جہان کی دائمی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے
ان انعامات کا وارث بننا ہے تو خدا تعالیٰ پر کامل ایمان رکھتے ہوئے اُس کی رضا کی راہوں کو
تلاش کرنے کی ضرورت ہے.اپنے مقصد پیدائش کو پہچاننے کی ضرورت ہے.یہ پہلی آیت جو میں نے پڑھی تھی، یہ نکاح پر پڑھی جانے والی آیتوں میں سے بھی ایک
آیت ہے.اللہ تعالیٰ اس میں جہاں انسان کو خود آئندہ زندگی کی فکر کی طرف توجہ دلا رہا
ہے، وہاں آئندہ پیدا ہونے والی نسل کی تربیت اور اُن کو دنیا کے بجائے نیکیوں میں آگے
بڑھنے کی طرف توجہ دلانے کا بھی ارشاد فرما رہا ہے.خاص طور پر جو آیات نکاح میں پڑھی
جانے والی ہیں یہ اُن میں سے ایک آیت ہے.کیونکہ نیک اولاد، اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل
618
Page 627
کرنے کی کوشش کرنے والی اولاد جہاں اپنی عاقبت سنوار نے والی ہوگی ، وہاں نیک اولاد
کے عمل اور اُن کی دعائیں جو وہ والدین کے لئے کر رہے ہیں، والدین کے درجات اگلے جہان
میں بھی بلند کرنے کا باعث بن رہی ہوں گی.پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنی شادی کے موقع پر بھی یہ بات یاد رکھو کہ دنیا اور اس کی تمام
آسائشیں، آسانیاں، مزے اور لذتیں عارضی چیز ہیں.شادی اور دنیاوی ملاپ یہ سب عارضی
لذات ہیں.اصلی لذت خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول میں ہے جو اس دنیا میں بھی ملتی ہے اور اس
کے پھل ایک مومن پھر اگلے جہان میں بھی کھاتا ہے.پس ایک مومن کو بار بار مختلف رنگ
میں اللہ تعالی تنبیہ اور تلقین فرماتا ہے کہ خدا تعالیٰ کو کبھی نہ بھولو، تقویٰ پر قائم رہو، ایسے اعمال بجا
لاؤ جو اس جہان کو بھی اور اگلے جہان کو بھی سنوارنے والے ہوں.اس جہان میں بھی تم اللہ تعالیٰ
کی رضا حاصل کرنے والے بنو اور آئندہ زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے بنو
اور یا درکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل کی خبر رکھنے والا ہے.اُس کی نظر سے انسان کا کوئی
چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی پوشیدہ نہیں ہے.ہر عمل کا حساب کتاب رکھا جارہا ہے.اس لئے انسان
کو بہت پھونک پھونک کے اس دنیا میں اپنے قدم اُٹھانے کی ضرورت ہے.ایمان لانا اور ایمان
کا دعویٰ کرنا صرف کافی نہیں ہے بلکہ تقویٰ کی راہوں کی تلاش اور ان پر عمل ضروری ہے.حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک مجلس میں فرماتے ہیں کہ :
اسلام میں حقیقی زندگی ایک موت چاہتی ہے جو تلخ ہے.لیکن جو اُس کو قبول کرتا ہے آخر
وہی زندہ ہوتا ہے.حدیث میں آیا ہے کہ انسان دنیا کی خواہشوں اور لذتوں کو ہی جنت سمجھتا
ہے حالانکہ وہ دوزخ ہے.اور سعید آدمی خدا کی راہ میں تکالیف کو قبول کرتا ہے اور وہی جنت
ہوتی ہے.اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا فانی ہے اور سب مرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں.آخر ایک وقت آجاتا ہے کہ سب دوست، آشنا، عزیز واقارب جدا ہو جاتے ہیں.اس وقت
جس قدر نا جائز خوشیوں اور لذتوں کو راحت سمجھتا ہے وہ تلخیوں کی صورت میں نمودار ہو جاتی ہیں.619
Page 628
سیٹی خوشحالی اور راحت تقویٰ کے بغیر حاصل نہیں ہوتی اور تقویٰ پر قائم ہونا گویا زہر کا پیالہ پینا
ہے.( یعنی بظاہر بہت مشکل کام ہے ) متقی کے لیے خدا تعالیٰ ساری راحتوں کے سامان
مہیا کر دیتا ہے.(لیکن جب انسان تقویٰ اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ساری راحتوں کے
سامان مہیا کر دیتا ہے ) فرمایا مَن يَتَّقِ اللهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ.(سورة الطلاق 3-4) پس خوشحالی کا اصول تقویٰ ہے.لیکن حصول تقوی کے لئے نہیں چاہئے
کہ ہم شرطیں باندھتے پھریں.تقویٰ اختیار کرنے سے جو مانگو گے ملے گا.خدا تعالیٰ رحیم
و کریم ہے.تقویٰ اختیار کرو جو چاہو گے وہ دے گا“.( ملفوظات جلد سوم صفحہ 90.ایڈیشن 2003، مطبوعہ ربوہ )
یعنی شرط یہ نہیں رکھنی چاہئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دے تو ہم نیکیاں کریں.بلکہ نیکیاں کرو،
تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرو، پھر اللہ تعالیٰ سے ایسا تعلق پیدا ہو جاتا ہے جو
مانگو وہ دیتا بھی ہے.پس تقویٰ پر چلنے سے انسان اللہ تعالیٰ کے ہر قسم کے انعامات کو حاصل کرنے والا بن سکتا
ہے، بن جاتا ہے.لیکن ہمیں ہر وقت اپنے جائزے لیتے رہنے کی بھی ضرورت ہے کہ ہم نے
دین کو دنیا پر مقدم کرنے کا عہد کیا ہوا ہے.اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ
والسلام کے ہاتھ پر بیعت کر کے تقویٰ پر چلنے کا عہد کیا ہے.اس لئے ہم نے اپنے قول وفعل
کو ایک کرنا ہے.حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ :
تقویٰ کا مرحلہ بڑا مشکل ہے.اُسے وہی طے کر سکتا ہے جو بالکل خدا تعالیٰ کی مرضی پر
چلے.جو وہ چاہے وہ کرے.اپنی مرضی نہ کرے.بناوٹ سے کوئی حاصل کرنا چاہے تو ہر گز نہ
ہوگا.( تقویٰ ایسی چیز نہیں کہ بناوٹ سے حاصل ہو جائے.یہ
کبھی نہیں ہو سکتا ) اس لیے
خدا کے فضل کی ضرورت ہے اور وہ اسی طرح سے ہو سکتا ہے کہ ایک طرف تو دعا کرے اور
620
Page 629
ایک طرف کوشش کرتا رہے.خدا تعالیٰ نے دعا اور کوشش دونو کی تاکید فرمائی ہے.“
پھر آپ فرماتے ہیں کہ :
( ملفوظات جلد سوم صفحہ 492.ایڈیشن 2003، مطبوعہ ربوہ )
کوئی پاک نہیں بن سکتا جب تک خدا تعالیٰ نہ بناوے.جب خدا تعالیٰ کے دروازہ پر
تذلل اور عجز سے اس کی روح گرے گی تو خدا تعالیٰ اس کی دعا قبول کرے گا اور وہ متقی بنے گا اور
اس وقت وہ اس قابل ہو سکے گا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سمجھ سکے.(عاجزی
اور تذلل اختیار کرو.اس کے لئے اللہ تعالیٰ کا فضل چاہئے.فضل ہوگا تو یہ ملے گا.اور جب یہ
ملے گا تو تقویٰ حاصل ہوگا.اور جب تقویٰ حاصل ہوگا تو تبھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دین یا
اسلام کی حقیقت کو انسان سمجھ سکے گا ).فرمایا : ”اس کے بغیر جو کچھ وہ دین دین کر کے پکارتا
ہے اور عبادت وغیرہ کرتا ہے وہ ایک رسمی بات اور خیالات ہیں کہ آبائی تقلید سے سن سنا کر بجا
لاتا ہے.( کہ باپ دادا یہ کر رہے ہیں، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا ، مسلمان ہوں.احمدی
کے گھر میں پیدا ہوا، احمدی مسلمان ہوں.تو اُس کی تقلید میں یہ کام کر رہا ہے.یہ نہیں، اصل چیز
تقویٰ ہے اور تقویٰ حاصل ہوتی ہے کوشش اور عمل سے، عاجزی اور انکساری اختیار کرنے
سے، دعا کرنے سے.فرمایا کہ یہ جو آبائی تقلید سے سن سنا کر بجالاتا ہے.کوئی حقیقت اور
روحانیت اس کے اندر نہیں ہوتی.“
( ملفوظات جلد سوم صفحہ 493.ایڈیشن 2003ء مطبوعہ ربوہ )
صرف نری تقلید جو ہے، اس سے روحانیت پیدا نہیں ہوتی.پھر آپ فرماتے ہیں کہ : ” تقویٰ حاصل کرو کیونکہ تقویٰ کے بعد ہی خدا تعالیٰ کی برکتیں
آتی ہیں.متقی دنیا کی بلاؤں سے بچایا جاتا ہے.“
( ملفوظات جلد سوم صفحہ 572.ایڈیشن 2003ء مطبوعہ ربوہ )
اللہ تعالیٰ کے فضل سے من حیث الجماعت بیشک اللہ تعالیٰ کے بیشمار فضل ہم جماعت پر
دیکھتے ہیں، جماعت کی ترقی بھی ہم دیکھتے ہیں.اللہ تعالیٰ کا جماعت کے ساتھ ایک خاص
621
Page 630
سلوک بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح انتہائی نامساعد حالات میں بھی جماعت کو اللہ تعالیٰ دشمن
کے منہ سے نکال لاتا ہے.جماعت کی ایک اچھی تعداد یقیناً تقویٰ پر چلنے والوں اور اللہ تعالیٰ
کی رضا حاصل کرنے والوں کی بھی ہے.لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہئے کہ حضرت مسیح موعود
علیہ الصلوۃ والسلام سے عہد بیعت باندھ کر ہم میں سے ہر ایک وہ معیار تقویٰ حاصل کرے، وہ خدا
تعالیٰ کا قرب ہمیں حاصل ہو جو ایک حقیقی مسلمان
کا ہونا چاہئے اور جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ
والسلام ہم سے چاہتے ہیں.اور وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ ہم خدا تعالیٰ کو ہمیشہ یادرکھیں.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا تو اللہ تعالیٰ کا تو کچھ حرج نہیں کرو
گے.اللہ کا تو اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، ہاں یہ غفلت خود تمہیں نقصان پہنچانے والی ہو
یہ
گی.خدا تعالیٰ کو بھلانے والے وہ لوگ ہیں جو ایمان میں کمزور ہیں، کامل ایمان نہیں رکھتے ، یا
بھول جاتے ہیں کہ ہم نے ایک دن اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونا ہے اور اس وجہ سے پھر ایسے
عمل ہونے لگتے ہیں جن سے اُن کی اخلاقی اور روحانی حالت انحطاط پذیر ہو جاتی ہے، گرنے
لگ جاتی ہے، دنیا دین پر مقدم ہو جاتی ہے، نہ یہ کہ دین دنیا پر مقدم ہو.ایسے دنیا دار اگلے
جہان میں خدا تعالیٰ کا کیا سلوک دیکھیں گے وہ تو خدا تعالیٰ بہتر جانتا ہے.لیکن اس دنیا میں بھی
اُن کے دنیا میں پڑنے کی وجہ سے اُن کا ذہنی سکون برباد ہو جاتا ہے.کئی لوگ ہم دیکھتے ہیں
ذرا سے مالی نقصان پر دنیا وی نقصان پر ایسے روگ لگاتے ہیں کہ پھر کسی قابل نہیں رہتے.پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایمان کا دعویٰ ہے اور تقویٰ پر قدم مارنے کی کوشش نہیں
ہے.ایمان کے دعوے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حقوق اور اُس کے بندوں کے حقوق ادا کرنے
کی طرف توجہ نہیں ہے.تو یہ بات صاف ظاہر کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کامل نہیں ہے.جب ایمان میں کمزوری ہے اور اصلاح کی طرف توجہ نہیں ہے تو پھر دنیا میں بے سکونی کی
زندگی ہوگی.اور یہی نہیں، ایسا شخص پھر فاسقوں میں شمار ہوگا.فاسق کے یہاں یہ معنی ہوں گے
که احکام شریعت کو اپنے اوپر لاگو کرنے کا عہد کر کے پھر بعض یا تمام احکام کی خلاف ورزی
622
Page 631
کرنا.پھر قرآن کریم میں اور جگہوں پر اگر ہم دیکھیں ، ان آیتوں کی رُو سے یہ معنی بھی ملتے ہیں
کہ نعمت الہی کی ناشکری کر کے دائرہ اطاعت سے خارج ہونا.یا جو اللہ تعالیٰ کی نعمت کی
ناشکری کرے گاوہ دائرہ اطاعت سے باہر نکلا ہوا سمجھا جائے گا اور یوں فاسقوں یا بد کرداروں
میں شمار ہوگا.حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کر کے ہم نے یہ عہد کیا ہے کہ دین کو دنیا پر
مقدم رکھیں گے.جو بھی حالات ہوں، کبھی بھی خدا تعالیٰ کے احکامات کو نہیں بھلائیں
گے.دوسرے ایک احمدی پر اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ اُسے اُس نعمت سے حصہ دیا ہے جو
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو آگے بڑھانے اور اسلام کی تجدید کے لئے اللہ تعالیٰ نے
حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت میں بھیجی ہے.اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے تو
سب سے بڑی نعمت نبوت کی نعمت ہے جس کے لئے مسلمانوں میں عجیب دو عملی دیکھتے ہیں کہ
دعا بھی مانگتے ہیں اور انکار بھی کرتے ہیں.اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے کہ ہم وہ خوش قسمت
لوگ ہیں کہ ہمیں اس نے اس نعمت کو قبول کرنے کی توفیق دی جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
غلامی میں اور آپ کے طفیل ملنے والی نعمت تھی اور ہم اُن لوگوں میں شمار ہوئے جو اس انعام میں
سے حصہ پانے والے ہیں اور حقیقت میں انعام سے حصہ پانے والے اور اس کی شکر گزاری ادا
کرنے والے ہم تبھی ہو سکتے ہیں جب ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات
اور توقعات پر پورا اترنے والے ہوں، اس کے لئے کوشش کرنے والے ہوں.ورنہ ہم اللہ
تعالیٰ کو بھلانے والے اور اپنی غفلتوں میں ڈوب جانے والے ہوں گے اور نتیجہ خدا تعالیٰ کی
ناراضگی مول لینے والے ہوں گے.ہمیں ہمیشہ یادرکھنا چاہئے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ
والسلام اپنے آقا و مطاع حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں توحید کے قیام کے
لئے اور اللہ تعالیٰ کے وجود کو ثابت کرنے کے لئے آئے تھے اور حقیقی تقویٰ بھی اُسی وقت قائم
ہوتا ہے جب خدا تعالیٰ کی وحدانیت پر کامل یقین ہو اور اُس کی رضا مقصود و مطلوب ہو اور خدا
623
Page 632
تعالی کی توحید میں انسان کھویا جائے اور جب یہ ہو جائے تو حقیقی تقویٰ انسان میں پیدا ہوتا ہے.حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ :
ال
توحید صرف اِس بات کا نام نہیں کہ منہ سے لا إلهَ إِلَّا اللہ کہیں اور دل میں ہزاروں بُبت
جمع ہوں.بلکہ جو شخص کسی اپنے کام اور مکر اور فریب اور تدبیر کو خدا کی سی عظمت دیتا ہے یا کسی
انسان پر بھروسہ رکھتا ہے جو خدا تعالیٰ پر رکھنا چاہئے یا اپنے نفس کو وہ عظمت دیتا ہے جو خدا کو
دینی چاہئے ان سب صورتوں میں وہ خدا تعالیٰ کے نزدیک بت پرست ہے.بت صرف وہی
نہیں ہیں جوسونے یا چاندی یا پیتل یا پتھر وغیرہ سے بنائے جاتے ہیں اور اُن پر بھروسہ کیا جاتا
ہے بلکہ ہر ایک چیز یا قول یا فعل جس کو وہ عظمت دی جائے جو خدا تعالیٰ کا حق ہے وہ خدا تعالیٰ
کی نگاہ میں بت ہے“.فرمایا: "یادر ہے کہ حقیقی تو حید جس کا اقرار خدا ہم سے چاہتا ہے اور
جس کے اقرار سے نجات وابستہ ہے یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کو اپنی ذات میں ہر ایک شریک سے
خواہ بت ہو، خواہ انسان ہو، خواہ سورج ہو یا چاند ہو یا اپنا نفس، یا اپنی تدبیر اور مکر فریب ہو، منزہ
سمجھنا اور اس کے مقابل پر کوئی قادر تجویز نہ کرنا.کوئی رازق نہ ماننا.کوئی معز اور مذل خیال
نہ کرنا.( یعنی یہ ہمیشہ یادرکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بالا ہے اور دنیا کی کوئی چیز، ہر عزت اور
ذلت جوانسان کو ملتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، کوئی انسان نہ کسی کو معزز بنا سکتا
ہے نہ ذلیل کر سکتا ہے.پس یہ ہے توحید کا اصل کہ اللہ تعالی ہی کو عزت دینے والا اور ذلت
دینے والا سمجھنا.اللہ تعالیٰ ہی ہے جو انسان کو عزتوں کا مالک بھی بناتا ہے اور اگر اُس کے غلط
کام ہوں تو اُس کو ذلیل ورسوا بھی کرتا ہے.)
پھر فرمایا کہ : ” کوئی ناصر اور مددگار قرار نہ دینا.“ ( خدا تعالیٰ کے علاوہ کوئی مددگار نہ
ہو.) اور دوسرے یہ کہ اپنی محبت اُسی سے خاص کرنا.اپنی عبادت اُسی سے خاص کرنا.اپنا
تذلل اُسی سے خاص کرنا ( بعض لوگ جو انسانوں کے آگے جھکتے ہیں، فرمایا نہیں، ہر قسم کی
عاجزی اور تذلل صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے ہو.) اپنی امید میں اُسی سے خاص کرنا.اپنا خوف
624
Page 633
اُسی سے خاص کرنا (.فرمایا: ) پس کوئی تو حید بغیر ان تین قسم کی تخصیص کے کامل نہیں ہو
سکتی.اوّل ذات کے لحاظ سے توحید.یعنی یہ کہ اُس کے وجود کے مقابل پر تمام موجودات کو
معدوم کی طرح سمجھنا.یعنی ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے ) اور تمام کو بالکۃ الذات اور
باطلة الحقیقت خیال کرنا ( یعنی ہر چیز اپنی ذات میں فنا ہونے والی ہے اور حقیقت میں کسی
چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے.) دوم صفات کے لحاظ سے توحید.یعنی یہ کہ ربوبیت اور
الوہیت کی صفات بجز ذات باری کے کسی میں قرار نہ دینا ( پالنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے اور
عبادت کے لائق بھی صرف وہی ہے.اور جو بظاہر رب الانواع یا فیض رسان نظر آتے
ہیں.( جولوگ بظاہر فائدہ دیتے ہیں، دنیاوی فائدے لوگوں سے پہنچتے ہیں.اللہ تعالیٰ نے
انسانوں کو ذریعہ بنایا ہوا ہے اُن سے فائدے بھی پہنچتے ہیں ، وہ پرورش کا ذریعہ بھی بن جاتے
ہیں ) یہ اُسی کے ہاتھ کا ایک نظام یقین کرنا ( اُن کے بارے میں یہ سمجھنا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا
نظام ہے.اللہ تعالیٰ نے کسی کو ذریعہ بنایا ہے، نہ کہ وہ خود اس چیز کو دینے کے مالک ہیں.اصل مالک اللہ تعالیٰ ہے اور یہ لوگ ذریعہ ہیں.)
( فرمایا : ” تیسرے اپنی محبت اور صدق اور صفا کے لحاظ سے توحید.یعنی محبت وغیرہ شعار
عبودیت میں دوسرے کو خدا تعالیٰ کا شریک نہ گرداننا ( یعنی یہ جو توحید اور محبت ہے اس میں
عبودیت کے جو شعار ہیں دوسرے کو خدا تعالیٰ کا شریک نہ گرداننا) اور اسی میں کھوئے جانا.“
( سراج الدین عیسائی کے چار سوالوں کا جواب.روحانی خزائن جلد 12 صفحہ 349-350)
صرف یہی نہیں کہ خدا تعالیٰ کا شریک نہیں بنانا بلکہ اس میں کھوئے جانا، اس میں ڈوب
جانا ، خدا تعالیٰ کی ذات میں اپنے آپ کو فنا کر لینا.پس یہ باتیں اگر ایک مومن میں ہوں تو وہ خدا تعالیٰ کو یا در کھنے کا حق ادا کرنے والا کہلا سکتا
ہے، تقویٰ پر چلنے والا کہلا سکتا ہے.تقویٰ کے کمال کے بارے میں حضرت مسیح موعود
علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ یہ فرمایا ہے کہ کمال تقویٰ کا یہی ہے کہ انسان کا اپنا وجود ہی نہ
رہے.پھر فرمایا کہ اصل میں یہی تو حید ہے.جب انسان اس کمال کو حاصل کر لیتا ہے کہ اپنا
625
Page 634
وجود نہیں رہتا ، اللہ کے وجود میں کھویا جاتا ہے، تو یہ تقویٰ کا کمال ہے اور اصل میں یہی توحید
ہے.جب اس مقام
پر پہنچ جاتا ہے تو وہ حقیقی تو حید کا ماننے والا کہلاتا ہے.پس اللہ تعالیٰ کی
ذات کو ہر چیز پر مقدم کر لینا یہی تقویٰ ہے اور یہی تو حید پر قائم ہونا ہے.اللہ تعالیٰ ہمیں یہ معیار
حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.ه مه ای اس اس د الله مرور 20 می 2013 - خطبات مسرور جلد 1 سحر 26 -269)
حضرت خلیفۃ اسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے سورۃ الحشر کی آیات 19 اور 20
کی تلاوت کے بعد فرمایا:
یہ سورہ حشر کی دو آیات ہیں جن کا ترجمہ اس طرح پر ہے کہ
اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور ہر جان یہ نظر رکھے کہ وہ کل کے لئے
کیا آگے بھیج رہی ہے.اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرو.یقینا اللہ اس سے جو تم کرتے ہو ہمیشہ باخبر
رہتا ہے.اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں خود اپنے
آپ سے غافل کر دیا.یہی بدکردار لوگ ہیں.عموماً دیکھا جاتا ہے کہ ہر برائی اور گناہ کی جڑ ان برائیوں اور گناہوں کو معمولی سمجھتے ہوئے
ان سے بچنے کی کوشش نہ کرنا ہے یا ان پر توجہ نہ دینا ہے لیکن یہی بے احتیاطی پھر انسان کو
بڑے گناہوں میں مبتلا کر دیتی ہے کیونکہ پھر انسان آہستہ آہستہ نیکیوں کو بھول جاتا ہے نیکی
کے ان معیاروں کو بھول جاتا ہے جو ایک مومن کو حاصل کرنے چاہئیں.اللہ تعالیٰ کا خوف کم
ہوجا تا ہے.تقویٰ سے دوری ہو جاتی ہے.مرنے کے بعد کی زندگی پر کامل ایمان نہیں رہتا.گویا کہ ایک ایمان کا دعویٰ کرنے والا عملاً ایمان کی شرائط سے دُور ہٹتا چلا جاتا ہے اور اللہ
تعالی کی نظر میں پھر مومن نہیں رہتا.ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اسی طرف مومنوں کی توجہ
دلائی ہے.اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بڑا زور دے کر فرمایا کہ صرف آج کی اور اس دنیا کی لہو ولعب کی
دلچسپیوں کی ، آراموں اور آسائشوں کی یا عزیزوں رشتہ داروں اور دوستوں سے تعلقات کی فکر نہ
626
Page 635
کرو بلکہ جوفکر کرنے والی چیز ہے وہ تمہاری کل ہے.تمہارا اللہ تعالیٰ پر ایمان کا معیار اور اس کا
تقویٰ اختیار کرنا تمہاری اصل ترجیح اور فکر ہونی چاہئے.تمہارا مرنے کے بعد کی زندگی اور
حساب کتاب پر ایمان تمہاری فکر کا مرکز ہونا چاہئے.اور اگر یہ ہوگا تو تبھی تمہاری حقیقی اخلاقی
ترقی بھی ہوگی جو صرف سطحی اخلاق نہیں ہوں گے بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کا مقصود
لئے ہوئے ہوں گے.تمہاری روحانی ترقی اور یہ دعویٰ کہ میں مومن ہوں اسی وقت حقیقی ہوگا
جب کل پر نظر ہوگی.تمہارا یقینی، بے غرض اور سچائی پر مبنی خدا تعالی کی ذات پر ایمان بھی اُس
وقت اللہ تعالیٰ کی نظر میں حقیقی ہوگا جب اپنے کل کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضا کے
حصول کی کوشش کرو گے اور اس کے حکموں پر عمل کرنے کی کوشش کرو گے.جو پہلی آیت میں نے تلاوت کی ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس بارے میں فرماتے
ہیں کہ :
”اے ایمان والو خدا سے ڈرتے رہو اور ہر یک تم میں سے دیکھتا رہے کہ میں نے اگلے
جہان میں کونسا مال بھیجا ہے اور اس خدا سے ڈرو جو خبیر اور علیم ہے اور تمہارے اعمال دیکھ رہا
ہے.یعنی وہ خوب جاننے والا اور پر کھنے والا ہے.اس لئے وہ تمہارے کھوٹے اعمال ہرگز
قبول نہیں کرے گا.“
ست بچن، روحانی خزائن جلد 10 صفحہ 225_226)
پس اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو ہم میں سے ہر ایک کو بڑے غور اور کوشش سے سمجھنے کی
ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرتے ہوئے ہم اپنے اعمال پر نظر رکھیں.ان باتوں پر
نظر رکھیں جو ہماری کل سنوارنے والی ہیں.اللہ تعالیٰ جو ہمارے دلوں کی پاتال تک نظر رکھنے والا
ہے اور اسے ہمارا سب علم ہے اس کو صرف ان باتوں سے دھوکہ نہیں دیا جا سکتا جو سطحی باتیں
ہیں بلکہ جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کھوٹے کھرے کی تمیز کرتا ہے.کھوٹے اعمال وہ قبول نہیں کرے گا.پس ایک مومن کے لئے یہ بہت بڑا فکر کا مقام ہے کہ
اپنے کل کی فکر کریں جہاں اعمال کا حساب ہونا ہے.غیر مومنوں کی طرح ہم صرف اس دنیا ہی کو
627
Page 636
سب کچھ نہ کھولیں بلکہ حقیقی کامیابیوں کو حاصل کرنے کے لئے تقویٰ پر چلیں.حضرت خلیفہ امسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ : دنیا و عقبی میں کامیابی کا ایک گر
اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ انسان کل کی فکر آج کرے.اس سے دنیا میں بھی سنوار پیدا ہوگا اور
آخرت کی زندگی میں بھی سنوار پیدا ہوگا.پھر آپ نے فرمایا کہ قرآن پاک کی تعلیم وَلتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ پر عمل کرنے
سے انسان نہ صرف دنیا میں کامران ہوتا ہے بلکہ عقلی میں بھی خدا کے فضل سے سرخرو ہو گا.ہم کبھی
آخرت کے لئے سرمایہ نجات جمع نہیں کر سکتے جب تک آج ہی سے اس دار القرار کے لئے
تیاری نہ شروع کردیں.“
( حقائق الفرقان جلد چہارم صفحہ 66-67)
اس حوالے سے میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ آیت نکاح کے خطبے میں بھی ہم پڑھتے ہیں.یہ نکاح کے خطبے میں پڑھی جانے والی آیات میں سے سب سے آخری آیت ہے.اللہ تعالیٰ
نے نکاح کے خطبہ میں پڑھی جانے والی آیات میں مختلف امور کی طرف توجہ دلا کر کہ اپنے رحیمی
رشتوں کا بھی خیال رکھو.اس بندھن کے ساتھ جو ذمہ داریاں پڑنے والی ہیں ان کا بھی خیال
رکھو.سچائی اختیار کرو.سچائی پر قائم رہو گے تو اس کے ذریعہ سے نیک اعمال کی اور رشتے
نبھانے کی توفیق ملتی رہے گی.اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات پر چلو اس میں تمہاری
کامیاب زندگی ہے.پھر مزید زوردیا کہ اگر کل پر نظر رکھو گے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے
احکامات پر بھی نظر رہے گی.اب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے بیشمار احکامات ہیں جو عائلی
معاملات کو خوبصورت بنانے میں کردار ادا کرتے ہیں.اگر انسان غور کرے تو اس کا فائدہ
انسان کو ہی ہے.جیسا کہ حضرت خلیفہ اول نے یہ فرمایا کہ دنیا بھی سنور جائے گی اور عقبی بھی
سنور جائے گی.اس دنیا میں گھریلو زندگی بھی جنت نظیر بن جائے گی اور اللہ تعالیٰ کے حکموں پر
عمل کرنے سے آخرت کے انعامات بھی ملیں گے.پھر صرف اپنی ذات تک ہی نہیں بلکہ
اس وجہ سے اولاد بھی نیکیوں پر چلنے والی ہوگی.گویا صرف اپنی کل نہیں سنوار رہے ہوں گے بلکہ
628
Page 637
اگلی نسل کی کل کی بھی ایک حقیقی مومن ضمانت بننے کی کوشش کرے گا.بلکہ ضمانت بن جاتا
ہے کہ عموماً پھر آئندہ نسل بھی نیکیوں پر قدم مارنے والی ہوگی.پس اگر وہ گھر یا وہ خاندان جو اپنے گھروں کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر برباد کر رہے ہوتے ہیں
اللہ تعالیٰ کے حکموں پر غور کرنے والے اور ان پر عمل کرنے والے بن جائیں تو نہ صرف اپنے
گھروں کے سکون کے ضامن ہو جائیں گے، اپنے بچوں کی صحیح تربیت اور ان کو تقویٰ پر چلنے کی
طرف رہنمائی کرنے والے بھی بن جائیں گے اور ان کی زندگیاں سنوارنے والے بھی بن
جائیں گے بلکہ اللہ تعالیٰ کے انعامات اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی حاصل کرنے والے
بن جائیں گے.پس ایسے گھروں کو جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر صرف دنیا داری کی خاطر اپنے
گھروں
کو برباد کر رہے ہیں سوچنا اور غور کرنا چاہئے.اگلی نسلیں صرف آپ ہی کی اولاد نہیں ہیں
بلکہ جماعت اور قوم کا بھی سرمایہ ہیں.ان کو صحیح راستے دکھانا ماں باپ کا کام ہے اور یہی بھی ہو
سکتا ہے جب ماں باپ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق
چلانے کی کوشش کرنے والے ہوں.اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے.یہ تو ایک پہلو ہے جس کی طرف ہر مومن کو اللہ تعالیٰ نے کوشش کرنے کی طرف اور عمل
کرنے کی طرف توجہ دلائی ہے تا کہ اپنی اور بچوں کی دنیا و آخرت سنوار سکیں.ہماری زندگی
میں بیشمار ایسے مواقع آتے ہیں جب ہم تقویٰ سے کام نہیں لیتے.آخرت پر نظر نہیں رکھتے.اس دنیا کے وسائل اور ضروریات کو ہی سب کچھ سمجھ لیتے ہیں.دنیا کے سہاروں کو اللہ تعالیٰ کے
سہاروں پر لاشعوری طور پر ترجیح دیتے ہیں.پھر اپنی کمزوریوں کی وجہ سے، نا اہلیوں کی وجہ
سے،سستیوں کی وجہ سے اس دنیا کے مستقبل کو بھی برباد کرتے ہیں.اس دنیا میں جو اپنی کل
ہے اس کو بھی برباد کرتے ہیں اور اگلے جہان کی کل کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں.یہ نہیں سوچتے
کہ اس کے کتنے بھیانک نتائج نکل سکتے ہیں.حضرت خلیفتہ المسیح الاول نے ایک دفعہ مختصر الفاظ میں یوں توجہ دلائی کہ مومن کو چاہئے
629
Page 638
کہ جو کام کرے اس کے انجام کو پہلے سوچ لے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا“.فرماتے ہیں کہ انسان
غضب کے وقت قتل کر دینا چاہتا ہے.گالی نکالتا ہے.مگر سوچے کہ اس کا انجام کیا ہوگا.اس
اصل کو مد نظر رکھے تو تقویٰ کے طریق پر قدم مارنے کی توفیق ملے گی.“
( حقائق الفرقان جلد چہارم صفحہ 67)
اگر ہم دیکھیں تو تمام برائیاں اور تمام گناہ اس لئے سرزد ہوتے ہیں کہ ان کے کرتے وقت
ہمارے دماغ میں ایک خناس سمایا ہوتا ہے، شیطان گھسا ہوتا ہے.نتائج سے بے پرواہ ہو کر
کام ہوتا ہے.بہت شاذ ایسا ہوتا ہے کہ قتل و غارتگری کرنے والے یا گناہ کرنے والے اقرار
کر کے خود اپنے آپ کو اس کے نتائج بھگتنے کے لئے پیش کر دیں.ایسے لوگوں کے جنون کی
کیفیت جو خود ہی پیش کرتے ہیں تقریباً مستقل کیفیت ہوتی ہے.باقی ہر عقل والا ، عام عقل
والا انسان جب اس جنونی کیفیت سے باہر آتا ہے تو اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا
ہے.عادی مجرموں کا معاملہ تو اور ہے وہ اس کے علاوہ ہیں.یہاں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی
بات نہیں فرما ر ہا جو عادی لوگ ہیں یا بالکل پاگل ہیں بلکہ ایمان کا دعویٰ کرنے والوں کو فرماتا
ہے کہ مومن کی نشانی کل پر نظر رکھنا ہے.حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کی وضاحت فرماتے ہوئے کہ نتائج پر یا کل
پر نظر رکھنے کا خیال کس طرح پیدا ہو، کس طرح نظر رکھی جائے.اس کے لئے آپ فرماتے
ہیں کہ اس بات پر ایمان رکھے کہ وَاللهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ.جو کام تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو اس
کی خبر ہے.انسان اگر یہ یقین رکھے کہ کوئی خبیر وعظیم بادشاہ ہے جو ہر قسم کی بدکاری، دغا،
فریب، سستی اور کاہلی کو دیکھتا ہے اور اس کا بدلہ دے گا تو وہ بیچ سکتا ہے“.آپ نے فرمایا
ایسا ایمان پیدا کرو.بہت سے لوگ ہیں جو اپنے فرائض نوکری ، حرفہ، مزدوری وغیرہ میں سستی
کرتے ہیں.ایسا کرنے سے رزق حلال نہیں رہتا“.( حقائق الفرقان جلد چہارم صفحه 67-68)
یعنی دنیاوی معاملات میں بھی جو سستی کرتے ہیں اور ان کا حق ادا نہیں کرتے تو اس کا
630
Page 639
مطلب ہے کہ انہوں نے بھی اپنی کل کو برباد کر لیا اور اپنا رزق جو انہوں نے حاصل کیا وہ بھی
حلال نہیں رہا.یہ دھو کے کا رزق ہے.پس یہ آیت جو اپنے کل پر نظر رکھنے کی طرف توجہ دلار ہی ہے بڑی وسعت رکھتی ہے اور ہر قدم
پر ایک حقیقی مومن کے پاؤں پکڑ کر کسی بھی معمولی کمزوری اور گناہ کی طرف بڑھنے سے روکتی ہے.پس یہ یقین ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے اور اس یقین پر ہم قائم ہوں کہ اللہ
تعالیٰ ہمارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے اور پھر اس بات پر بھی یقین کہ وہ ہمارے ہر قسم کے
دھو کے، فریب چاہے وہ ہم معمولی سمجھ کر تھوڑا سا منافع کمانے کے لئے کر رہے ہیں یا اپنے کام
میں سستی دکھا رہے ہیں یا معاہدے کے مطابق اس نیت سے جان بوجھ کر کام ختم نہیں کر رہے
که شاید کسی کو دباؤ میں لا کر مزید مفاد اٹھا سکیں تو یا درکھیں ایسی باتیں خدا تعالیٰ کو پسند نہیں.اور
جب خدا تعالیٰ کو پسند نہیں تو پھر جیسا کہ حضرت خلیفہ اول نے بھی فرمایا کہ اس کا بدلہ ہوگا اور
اس کا بدلہ پھر سزا کی صورت میں ہی ہے.پس مومن کو کل پر نظر رکھنے کا کہہ کر اپنے معمولی گھریلو معاملات سے لے کر اپنے معاشرتی،
کاروباری ہلکی، بین الاقوامی تمام معاملات میں تقویٰ پر چلنے کی طرف توجہ دلا دی اور جو تقویٰ پر
نہیں چلتا وہ پھر اس بات کو بھی ذہن میں رکھے کہ ایسا انسان خدا کی پکڑ میں آئے گا.انسان کو
یہ نہیں سمجھنا چاہئے کہ دنیاوی معاملات کا دین سے کوئی تعلق نہیں.مومن کے لئے تقویٰ پر چلنے
ہے اور تقویٰ میں تمام دینی اور دنیاوی کاموں کو خدا تعالیٰ کی ہدایات کے مطابق بجالانا
ضروری ہے.انسان بعض دفعہ سمجھتا ہے کہ دنیاوی نقصان کے ابتلا سے بچنے کی کوشش کروں.مالی منفعت حاصل کرلوں چاہے جو بھی ذریعہ اپنایا جائے.لیکن یادرکھنا چاہئے کہ کوئی ایسا طریق
جس سے دھوکہ دے کر فائدہ حاصل کیا جائے دین سے اور ایمان سے دور لے جانے والا ہے
اور یہ بظاہر دنیاوی معاملہ دینی ابتلا بن جاتا ہے اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ آہستہ آہستہ دین
اور خدا سے دور لے جاتا ہے.اس لئے ایک مومن کو ہمیشہ یادرکھنا چاہئے کہ ایمان کا ابتلا دنیاوی
ابتلاؤں سے بہت زیادہ ہے جس کے نتیجہ میں دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جاتی ہیں.631
Page 640
پس ہمیں اس سوچ کے ساتھ اپنے دلوں کو ٹو لتے رہنا چاہئے اور ہر کام کے انجام پر نظر رکھنی
چاہئے کہ خدا تعالیٰ کی میرے ہر کام پر نظر ہے.یہ سوچ جب پیدا ہو جائے تو مومن ایک حقیقی
مومن بن جاتا ہے یا بننے کی طرف قدم بڑھا رہا ہوتا ہے.اس معیار کو دیکھنے کے لئے کسی
جماعتی یا ذیلی تنظیم کے رپورٹ فارم کو دیکھنے اور اس پر انحصار کرنے کی ضرورت نہیں ہے.ہر
ایک شخص خود اپنے جائزے لے سکتا ہے کہ کیا یہ اس کے معیار ہیں کہ ہر کام کرنے سے پہلے
اسے یہ خیال آئے کہ خدا تعالیٰ میرے اس کام کو دیکھ رہا ہے.اگر میں نیک نیتی سے اللہ تعالیٰ
کی رضا حاصل کرنے کے لئے یہ کام کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ کا کئی گنا جزا کا بھی وعدہ ہے، اجر کا
بھی وعدہ ہے.اور اگر نیت بد ہے تو پھر انسان کو یہ سوچنا چاہئے کہ میں اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں بھی آ
سکتا ہوں.جب ہم میں سے ہر ایک ایسی سوچ کے ساتھ اپنے فرائض اور ذمہ داریاں ادا کرے
گا اور اس کے لئے کوشش کرے گا تو جماعت کے جو تقویٰ کے عمومی معیار ہیں وہ بھی بلند ہوں
گے اور یہ تقویٰ کا معیار بلند ہوتا ہوا جماعتی طور پر بھی خود بخود نظر آنا شروع ہو جائے گا.نہ تربیت
کے شعبے کے لئے مشکلات اور مسائل ہوں گے، نہ امور عامہ اور قضاء کے شعبے کے لئے
مسائل، نہ ہی دوسرے شعبوں کو یاد دہانیوں کی ضرورت اور فکر پڑے گی.پس اپنے دلوں کو ہر وقت صبح شام ٹولتے رہنا چاہئے اور شیطان کے حملوں سے نفس کو
بچانے کی انتہائی کوشش کی ضرورت ہے.اگر نہیں خیال آتے تو یہ شیطان کی وجہ سے ہی
نہیں آتے.اس بات کو بھلانے میں شیطان ہی کردار ادا کرتا ہے.خدا تعالیٰ کو بھلایا جائے تو
شیطان ہی ہے جو کردار ادا کرتا ہے.کل کی اگر فکر نہ ہوتو وہ شیطان ہی ہے جو بھلاتا ہے.یہ
شیطان ہی ہے جو یہ کہتا ہے اس بات کو بھول جاؤ کہ خدا تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے.اگر ہم جائزہ
لیں کہ اکثر اس بات کو نہیں سوچتے کہ میرے کام کو خدا تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور اس کا انجام کیا ہو
سکتا ہے اور یہ سب اس لئے ہوتا ہے جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان
انسان کے خون کے ساتھ اس کے جسم میں چلتا ہے.(صحیح البخاری کتاب الاعتكاف باب زيارة المرأة زوجہانی اعتکافہ حدیث نمبر 2038)
632
Page 641
بہت سی بیماریاں انسان کو اس لئے نقصان پہنچاتی ہیں کہ وہ خون میں گردش کر رہی ہوتی
ہیں.آہستہ آہستہ بڑھتی ہیں اور ایک وقت میں آ کر جسم پر بہت زیادہ اثر ڈالنا شروع کر دیتی
ہیں.کسی وجہ سے انفیکشن ہو جاتا ہے اور اس کا اثر ہو جاتا ہے تو انسان کو شروع میں پتا نہیں چلتا
کہ بیماری نے حملہ کر دیا ہے.بلکہ بہت ہی کوئی محتاط ہو، ذراسی کسل مندی کے بعد وہ ڈاکٹر
کے پاس جائے بھی تو ابتدائی حالت میں بعض ڈاکٹروں کو بھی پتا نہیں چلتا کہ بیماری اندر ہے،
خون میں گردش کر رہی ہے.اور یہ بیماریاں آتی ہیں جیسا کہ میں نے کہا فضا میں بعض دفعہ
جراثیم ہوتے ہیں ایک دوسرے سے بیماریاں لگتی ہیں اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں بہت ساری
و بائیں پھیلی ہوئی ہیں جن کا شروع میں پتا نہیں لگتا.آہستہ آہستہ جب پھیل جاتی ہیں تب پتا
لگتا ہے.لیکن آجکل کے زمانے میں جو سب سے خطرناک چیز ہے وہ اس زمانے میں
روحانی بیماریاں ہیں.اور روحانی بیماریوں کی تو فضا میں بھرمار ہوئی ہوئی ہے اور انسان کو پتا
نہیں لگتا کہ کس وقت شیطان ہمارے خون میں چلا گیا ہے اور روحانی بیماری کو بڑھانا شروع
کر دیا ہے.لیکن شیطان کے خون میں گردش کرنے سے جو بیماری آتی ہے وہ جسمانی بیماری کی
نسبت اس لحاظ سے زیادہ خطرناک ہے کہ جسمانی بیماری سے جسم پر اثرات پڑنے شروع
ہوتے ہیں.جسم ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے.کسل مندی کی کیفیت ہو جاتی ہے پھر آہستہ آہستہ
مزید تکلیف بڑھتی ہے.انسان خود محسوس کرتا ہے اور ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے کہ میں بیمار
ہوں مجھے دوائی دو لیکن روحانی بیماری خطر ناک اس وجہ سے ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے انسان
دور ہٹتا ہے اور شیطان کے حملے کے نیچے آ جاتا ہے تو تب بھی خود کو بیمار محسوس نہیں کرتا بلکہ
اپنے آپ کو اچھا ہی سمجھتا ہے.لیکن جب اس کے دوستوں، اس کے ہمدردوں کو پتا چلتا ہے کہ
یہ بیمار ہے تو وہ اس کو سمجھاتے ہیں.جو بیماری کی انتہا کو پہنچ جائیں وہ دوستوں کے کہنے پر بھی
خود کو بالکل ٹھیک سمجھتے ہیں اور اپنے عزیزوں اور دوستوں کو غلط سمجھتے ہیں.وہ سمجھتے ہیں کہ
میرے دوست مجھے غلط کہہ رہے ہیں.633
Page 642
پس شیطان کا حملہ یا روحانی بیماری جو ہے جسمانی بیماری سے بہت زیادہ خطرناک ہے
کیونکہ بسا اوقات اس کے علاج کے لئے انسان تیار نہیں ہوتا.دوسرے توجہ بھی دلائیں کہ
علاج کروالو تو اس طرف توجہ نہیں ہوتی.پس ایک مومن کو اس سے پہلے کہ بیماری حملہ کرے اپنے جائزے لیتے ہوئے حفظ ما تقدم
کے عمل کو شروع کر دینا چاہئے اور اس معاشرے میں جیسا کہ میں نے کہا کہ روحانی بیماریاں
مستقل فضا میں پھیلی ہوئی ہیں اس لئے اپنے آپ کو بچانے کے لئے مستقل عمل کی بھی ضرورت
ہے یا مستقل علاج کی بھی ضرورت ہے.حفظ ما تقدم کی ضرورت ہے اور یہی ایک حقیقی مومن
کے لئے ضروری ہے اور اس کو چاہئے کہ وہ اس کے لئے ہمیشہ کوشش کرتا رہے.ہمیشہ یادرکھنا چاہئے کہ مومن کبھی اللہ تعالیٰ کی خشیت اور خوف سے خالی نہیں ہوتا اور نہ ہونا
چاہئے.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ آپ جب بھی رات کو
اٹھتے تو نہایت عجز اور انکسار سے دعائیں کرتے.ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہانے
آپ کی اسی حالت کو دیکھ کر عرض کیا کہ آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ معاف کر دیا ہے.آپ کو اتنے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے.اتنی خشیت سے اپنے لئے دعائیں کیوں
کرتے ہیں؟ اپنے لئے اتنی خشیت کیوں ہے؟ (صحیح البخاری کتاب تفسیر القرآن باب
ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر...حدیث نمبر 4837) بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے تو یہ بھی فرمایا تھا جیسا کہ میں نے کہا کہ انسان کے خون میں شیطان ہے تو آپ نے فرمایا
تھا کہ میرا شیطان مسلمان ہو گیا ہے.(صحیح مسلم کتاب صفات المنافقین و احکامهم
باب تحريش الشيطان وبعثه..حدیث نمبر 7108) یعنی کسی روحانی بیماری کے حملہ آور ہونے
کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا.لیکن آپ نے فرمایا کہ میری نجات بھی خدا تعالیٰ کے فضل سے
ہے.مجھے بھی ہر وقت اس کی طرف جھکے رہنے کی ضرورت ہے.پس جب رسول کریم صلی اللہ
علیہ وسلم اس سب کے باوجود اس قدر خشیت کا اظہار کرتے ہیں تو پھر اور کون ہے جو کہہ سکے
634
Page 643
کہ مجھے ہر وقت ہر کام میں کل پر نظر رکھنے کی ضرورت نہیں اور کام کر کے پھر اللہ تعالیٰ کے
فضلوں کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں.پس ہر وقت ہشیار رہنے کی ضرورت ہے.ہر وقت
تقویٰ پر چلتے ہوئے اپنے کاموں اور اپنی حالتوں کے جائزے لینے کی ضرورت ہے.ہر وقت
اللہ تعالیٰ سے اس کا رحم مانگنے کی ضرورت ہے.ہر وقت یہ خیال دل میں رکھنے کی ضرورت ہے
کہ میں نے اپنے ایمان کو کس طرح بچانا ہے.اور اس کی طرف جو اگلی آیت میں نے تلاوت
کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہوجاؤ جنہوں نے اللہ تعالیٰ
کو بھلا دیا کیونکہ پھر اللہ تعالیٰ ان کو اپنے آپ سے غافل کر دے گا.جیسا کہ میں نے مثال دی ہے کہ روحانی بیماری والے اپنے آپ کو بیمار نہیں سمجھتے بلکہ ان
کے ہمدرد جب ان کو بیمار سمجھ کر ان کا علاج کروانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ الٹا ان
ہمدردوں کو بیمار اور پاگل سمجھنے لگ جاتے ہیں.گویا روحانی بیماری ان کو اپنے نفس کی حالتوں کو
دیکھنے سے بالکل لا پرواہ کر دیتی ہے اور پھر نتیجہ سوائے تباہی اور بربادی کے اور کچھ نہیں نکلتا.یا درکھنا چاہئے کہ عموماً انسان خدا تعالیٰ کو تین طریقوں سے بھلاتا ہے یا یہ تین قسم کے لوگ ہیں جو
ہمیں عموماً دنیا میں نظر آتے ہیں جو خدا تعالیٰ سے دُور ہیں یا دُور ہوتے ہیں.ایک تو وہ لوگ جو خدا تعالیٰ کے وجود کے انکاری ہیں اور بڑی ڈھٹائی سے کہہ دیتے ہیں
کہ خدا تعالی کوئی چیز نہیں ہے.جیسا کہ آج کل کی بہت بڑی تعداد اسی نظریے پر قائم ہے جو
اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہتے ہیں.اپنی تعلیم پر بڑا زعم ہے اور یہ لوگ میڈیا اور انٹرنیٹ اور
مختلف طریقوں سے نوجوانوں اور کچے ذہنوں کو اپنے خیالات سے زہر آلود کرتے رہتے ہیں.دوسرے وہ لوگ ہیں جن کو حقیقی اور سچا ایمان تمام طاقتوں والے خدا پر نہیں ہے جس کے
سامنے انہیں ایک دن پیش ہونا ہے اور اپنے اعمال کا جواب دینا ہے.باوجود اس کے کہ یہ
ایمان ہے یا اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ایک خدا ہے جس نے دنیا کو پیدا کیا ہے اور اس
کے تابع ایک نظام چل رہا ہے لیکن پھر بھی اس کے کہنے پر عمل نہیں ہے.635
Page 644
تیسرے وہ لوگ ہیں جو دنیا وی بکھیڑوں میں اس قدر ڈوب گئے ہیں کہ خدا تعالیٰ کو بھول
گئے ہیں.کبھی خیال آ جائے تو نماز بھی پڑھ لیں گے، دعا بھی کرلیں گے لیکن کوئی باقاعدگی نہیں
ہے.اس طرف توجہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مومن کے لئے پانچ نمازیں فرض کی ہیں.بہر حال یہ بات یقینی ہے کہ جو خدا تعالیٰ کو بھلاتے ہیں وہ آخر کا ر ایسی حالت کو پہنچ جاتے ہیں
جہاں ان کا اخلاقی انحطاط بھی ہوتا ہے اور روحانی تنزل بھی ہوتا ہے اور آخر کار ذہنی سکون بھی
جاتا رہتا ہے.وہ سمجھتے تو یہ ہیں کہ دنیا کے کاموں میں ان کے فوائد ہیں.اس لئے یہ تو پہلے کرو.خدا تعالیٰ کے حق بعد میں ادا ہوتے رہیں گے.کیونکہ دنیاوی منفعت میں بظاہر انتہ
رانہیں فوری
آرام اور آسائش نظر آ رہے ہوتے ہیں.لیکن جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایسے لوگوں
کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ ایسا سلوک کرتا ہے کہ فَأَنسَهُمْ أَنْفُسَهُمْ - اللہ تعالیٰ نے خود انہیں
اپنے آپ سے غافل کر دیا اور ایسے لوگ کبھی ذہنی سکون نہیں پاتے.پس مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر حقیقی تقویٰ تمہارے اندر ہے اور تم مومن ہو،
خدا تعالیٰ کے وجود پر یقین رکھتے ہو، اس کی وحدانیت پر ایمان ویقین ہے تو پھر ان شرائط کے
مطابق اپنی زندگی بسر کرو جن کے مطابق زندگی بسر کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے.اور وہ یہ
ہے کہ اپنے ہر کام کے انجام کو دیکھو اور اس یقین پر قائم ہو جاؤ کہ خدا تعالیٰ تمہارے ہر عمل اور
فعل کو دیکھ رہا ہے اور جب انسان کی ایسی سوچ ہو تو پھر ہر کام کرنے کا انداز ہی بدل جاتا ہے
اور انسان خود محسوس کرتا ہے کہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے فضل بھی مجھ پر بڑھ رہے ہیں.مجھے یاد ہے جب میں کینیا میں دورے پر گیا ہوں تو وہاں کے ایک پرانے سیاستدان تھے
جو ایک reception میں وہاں ملے.کہنے لگے کہ میں حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ
کو بھی ملا ہوں.انہوں نے مجھے ایک نصیحت کی تھی جس کا مجھے بڑا فائدہ ہوا ہے اور وہ نصیحت یہ
تھی کہ تم ہر کام کرنے سے پہلے یہ سوچ لو کہ خدا تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے اور اس کے پاس تمہاری
تمام باتوں کا ریکارڈ بھی ہے.اب مجھے یاد نہیں کہ مسلمان تھے یا عیسائی ، غالباً عیسائی تھے.اگر
636
Page 645
ان کو فائدہ ہوسکتا ہے تو ایک حقیقی مومن جس کو خاص طور پر خدا تعالیٰ نے تاکید فرمائی ہے اس
کو کس قدر فائدہ ہوگا کہ اپنے کام کے انجام پر نظر رکھے اور ہمیشہ یہ یادرکھے کہ علیم وقد یر خدا
میرے ہر کام اور ہر عمل کو دیکھ رہا ہے اور اسی وجہ سے میں نے اپنے ہر کام کو اس کی رضا کے
لئے کرنا ہے.اگر یہ سوچ نہیں ہوگی، خدا تعالیٰ کو بھول جاؤ گے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
فاسقوں میں شمار ہو گے.پس اللہ تعالیٰ نے یہاں فاسق کہہ کر ایمان کا دعویٰ کرنے والوں کو واضح کر دیا کہ اگر تقویٰ
پر نہیں چلتے.اپنے کل کی فکر نہیں کرتے.اللہ تعالیٰ کے حکموں پر نہیں چلتے تو پھر فاسقوں میں
شمار ہوگا اور فاسق وہ ہیں جو خدا تعالیٰ کی قائم کردہ حدود کو توڑنے والے ہیں.جو گناہوں میں مبتلا
رہنے والے ہیں.جو اطاعت سے نکلنے والے ہیں.جو سچائی سے دُور ہٹنے والے ہیں.پس اگر
ہم اپنے جائزے نہیں لیتے ، اپنے کاموں کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے معیار پر پرکھنے کی
کوشش نہیں کرتے تو بڑے خوف کا مقام ہے.حضرت خلیفہ المسیح الاول اس حصہ کی وضاحت فرماتے ہوئے ایک جگہ فرماتے ہیں کہ :
ایسے لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جن کی نسبت فرمایا کہ نَسُوا اللهَ فَأَنْسَهُمْ أَنْفُسَهُمْ
أوْلَئِكَ هُمُ الْفُسِقُونَ.یعنی جنہوں نے اس رحمت اور پاکی کے سر چشمہ قدوس خدا کو چھوڑ دیا
اور اپنی شرارتوں، چالاکیوں، ناعاقبت اندیشیوں، غرض قسم قسم کے حیلہ سازیوں اور
رو بہ بازیوں سے کامیاب ہونا چاہتے ہیں.“ ( رو بہ بازیوں کا مطلب ہے جو لومڑیوں کی طرح
چالاکیاں کرتے ہیں.اردو میں محاورہ ہے لومڑی کی طرح بڑا چالاک ہے.)
پھر آپ فرماتے ہیں کہ مشکلات انسان پر آتی ہیں.بہت سی ضرورتیں انسان کو لاحق ہیں.کھانے پینے کا محتاج ہوتا ہے.دوست بھی ہوتے ہیں.دشمن بھی ہوتے ہیں مگر ان تمام حالتوں میں
متقی کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ خیال اور لحاظ رکھتا ہے کہ خدا سے بگاڑ نہ ہو (یعنی خدا تعالیٰ کو ہر
وقت یا درکھتا ہے اور وہ اسے دوستوں پر بھی اور فائدہ مند چیزوں پر بھی مقدم رہتا ہے.)
637
Page 646
پھر فرمایا ” دوست پر بھروسہ ہو.ممکن ہے وہ دوست مصیبت سے پیشتر دنیا سے اٹھ
جاوے یا اور مشکلات میں پھنس کر اس قابل نہ رہے ) کہ کام آئے.پھر ) حاکم پر بھروسہ ہو تو
ممکن ہے کہ حاکم کی تبدیلی ہو جاوے اور وہ فائدہ اس سے نہ پہنچ سکے اور ان احباب اور
رشتہ داروں کو جن سے امید اور کامل بھروسہ ہو کہ وہ رنج اور تکلیف میں امداد دیں گے اللہ تعالیٰ
اس ضرورت کے وقت ان کو اس قدر ڈور ڈال دے کہ وہ کام نہ آسکیں.“
فرمایا کہ پس ہر آن خدا ( تعالی ) سے تعلق نہ چھوڑ نا چاہئے جوزندگی،موت کسی حالت میں
66
ہم سے جدا نہیں ہوسکتا.( زندگی اور موت میں خدا تعالیٰ کا ہی ساتھ ہے.)
فرمایا کہ پس خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے خدا تعالیٰ
سے قطع تعلق کر لیا ہے.اس
کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم دکھوں سے محفوظ نہ رہ سکو گے اور سکھ نہ پاؤ گے بلکہ
ہر طرف سے ذلت کی مار ہوگی اور ممکن ہے کہ وہ ذلت تم کو دوستوں ہی کی طرف سے آ
جاوے.ایسے لوگ جو خدا تعالیٰ سے قطع تعلق کرتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ فاسق، فاجر
ہوتے ہیں.ان میں سچا اخلاص اور ایمان نہیں ہوتا.یہی نہیں کہ وہ ایمان کے کچے ہیں.نہیں.ان میں شفقت علی خلق اللہ بھی نہیں ہوتی !.“
( حقائق الفرقان جلد چہارم صفحہ 68)
اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے شفقت بھی نہیں کرتے.یعنی نہ خدا کے حقوق ادا کرتے ہیں نہ بندوں
کے حقوق ادا کرتے ہیں.پس ہم میں سے ہر ایک کو اپنے ہر عمل کو خدا تعالیٰ کے حکموں کے مطابق کرنے کی
کوشش کرنی چاہئے.اپنے عارضی فائدوں کی بجائے اپنے کل پر نظر رکھیں.اللہ تعالیٰ ہمیں
اس کی توفیق عطا فرمائے.خطبه جمع حضر علیه است لاس ایده الله فرمود 06 مارچ 2015ء - خطبات مسرور جلد 13 صفحه 15 - 165)
حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے خطبہ جمعہ فرمودہ 6 جولائی
2007ء میں مندرجہ ذیل آیت قرآنی کی تلاوت اور ترجمہ بیان فرمایا:
638
Page 647
هُوَ اللهُ الَّذِى لَآاِلَة إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَمُ الْمُؤْمِنُ
الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ
(الحشر (24)
وہی اللہ ہے جس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، وہ بادشاہ ہے، پاک ہے، سلام ہے، امن
دینے والا ہے، نگہبان ہے، کامل غلبہ والا ہے،ٹوٹے کام بنانے والا ہے اور کبریائی والا ہے.پاک ہے اللہ اس سے جو شرک کرتے ہیں.بعد ازاں حضرت خلیفہ اُسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز اس آیت کی تشریح بیان
ایدہ
کرتے ہوئے فرماتے ہیں:
جیسا کہ اس آیت سے ظاہر ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک نام مؤمن ہے.جو تر جمہ میں نے
پڑھا ہے، اس میں مؤمن کے معنی امن دینے والے کے کئے گئے ہیں.پس ہر شخص کا انفرادی
امن بھی اور معاشرے کا امن بھی اور دنیا کا امن بھی اُس ذات کے ساتھ وابستہ رہنے سے ہے جو
امن دینے والی ذات ہے جس کا ایک صفاتی نام جیسا کہ آپ نے سنا المُؤْمِن ہے.پس اس
نام سے فیض بھی وہی پائے گا جو اللہ تعالیٰ کے حکم صبغۃ اللہ کہ اللہ کے رنگ میں رنگین ہو، پر
عمل کرنے کی کوشش کرے گا.اِس سے دُور ہو کر ہر امن کی کوشش رائیگاں جائے گی.ہر
کوشش کا آخری نتیجہ ذاتی مفادات کے حصول کی کوشش ہوگا نہ کہ امن.اور یہ امن اسی کو
مل سکتا ہے جن کا ایمان کامل ہو.اور اللہ تعالیٰ پر ایمان کامل تب ہو گا جب اللہ تعالیٰ کے تمام
انبیاء پر بھی ایمان ہو جیسا کہ اس نے فرمایا ہے.پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم الانبیاء
ہیں آپ پر ایمان لانا بھی اصل میں ایک مومن کو کامل الایمان بنا تا ہے.آپ کے ذریعہ سے
ہی اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء پر ایمان لانے کا حکم اتارا اور ایک مسلمان کو اس کا پابند کیا.اور
پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کو اس بات کا بھی پابند فرمایا کہ تاریک
زمانے کے بعد جب میرا مسیح و مہدی مبعوث ہو گا تو اسے ماننا، اسے قبول کرنا، اس کی بیعت
639
Page 648
میں شامل ہونا، یہ بھی تم پر فرض ہے اور وہ کیونکہ حکم اور عدل بھی ہو گا اس لئے قرآن کریم کے
معارف اور احکامات کی جو تشریح وہ کرے، جو وضاحت وہ کرے اس کو ماننا اور اس پر ایمان
لانا بھی ضروری ہے.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہی ہے جس نے تمام مسلمانوں
کو بھی اور غیر مسلموں کو بھی میرے نام پر ایک ہاتھ پر اکٹھا کرنا اور امت واحدہ بنانا ہے.پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے مطابق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ
والسلام کی بیعت میں شامل ہونے والے ہی اللہ تعالیٰ کی صفت مومن سے حقیقی فیض پانے
والے ہیں، ایمان میں بڑھنے والے ہیں، امن میں رہنے والے ہیں اور امن قائم کرنے والے
ہیں اور ہونے چاہئیں.یہ خصوصیات ہر احمدی میں ہونی چاہئیں.پس ہر احمدی کو اپنے ایمان
میں ترقی کرتے ہوئے اس اہم بات کو ہمیشہ اپنے پلے باندھے رکھنا چاہئے کہ صرف منہ سے
مان لینا کافی نہیں ہوگا بلکہ ایمان میں بڑھنا اس میں ترقی کرنا ، یہی ہے جو اسے اللہ تعالیٰ کی
صفت مومن سے حقیقی رنگ میں فیضیاب کرنے والا بنائے گا.ورنہ اگر تعلیم پر عمل نہیں تو اللہ
تعالیٰ کے حکم کے ایک حصہ کو تو مان لیا کہ ہم تمام انبیاء پر ایمان لاتے ہیں لیکن جو اللہ تعالیٰ
کے احکامات ہمیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے ملے اور جنہیں اس زمانے میں
آپ کے غلام صادق نے پھر خوبصورت انداز میں پیش کر کے ان پر عمل کرنے کی ہمیں نصیحت
فرمائی ، اس پر ہم پوری طرح کار بند ہونے کی کوشش نہ کر کے عملاً اپنے ایمان کو کمزور کر
رہے ہوں گے.اللہ تعالیٰ ہر احمدی کے ایمان کو مضبوط کرتا چلا جائے ، اسے اپنے ایمان کو
مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے تا کہ وہ اپنی ذات میں بھی اور اپنے معاشرے میں بھی اللہ
تعالیٰ کی صفت مومن کا حقیقی پر تو نظر آئے.مومن کے مزید معانی جو اہل لغت اور مفسرین نے بعد میں پیش کئے ہیں ، اب میں وہ بیان
کرتا ہوں.لسان العرب کے مطابق اللہ تعالیٰ کی صفت الْمُؤْمِن کا ایک معنی یہ کیا گیا ہے کہ
مومن وہ ہستی ہے جس نے اپنی مخلوق کو اس بات سے امن عطا کیا کہ ان پر ظلم کرے.بعض
640
Page 649
نے اس کے معنی یہ کئے ہیں کہ مومن وہ ذات ہے جس نے اپنے اولیاء کو اپنے عذاب سے امن
بخشا ہے.پہلے معنی وسعت کے لحاظ سے زیادہ وسیع دائرے میں ہیں.اللہ تعالیٰ کی رحمت تو ہر
چیز پر حاوی ہے، اس لئے ظلم کا تو سوال ہی نہیں.اللہ تعالیٰ کے اولیاء کو عذاب کا سوال کیا؟ وہ
تو خود بخود امن میں آجاتے ہیں.اللہ تعالیٰ کے اولیاء پر جو ابتلاء آتے ہیں، حضرت
مسیح موعود علیلا نے فرمایا ہے کہ وہ تو ان کا ایک امتحان ہوتا ہے جس میں سے وہ گزرتے ہیں
اور بجائے شکوہ کے اللہ تعالیٰ کی مدد اور دعاؤں سے اس میں سے گزر جاتے ہیں.ابوالعباس کہتے ہیں کہ عربوں کے نزدیک المؤمن کا معنی الْمُصَدِّق ہے اور مراد یہ ہے کہ
قیامت کے دن جب اللہ تعالی اُمتوں سے رسولوں کی تبلیغ سے متعلق سوال کرے گا تو وہ کسی بھی
رسول کی بعثت کا انکار کر دیں گے اور اپنے انبیاء کی تکذیب کریں گے.پھر امت محمدیہ لائی
جائے گی اور ان سے یہی سوال کیا جائے گا تو وہ سابقہ انبیاء کی بھی تصدیق کریں گے، اس پر
اللہ تعالیٰ ان کی تصدیق کرے گا.اس معنی میں اللہ تعالیٰ کو مومن یعنی المُصَدِّق کہا گیا ہے نیز
محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی تصدیق کریں گے اور یہی مضمون اس آیت کریمہ کا ہے جو
فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هُؤُلاء شَهِيدًا (النساء 42)
یعنی پس کیا حال ہو گا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لے کر آئیں گے اور ہم تجھے ان سب
پر گواہ بنا کر لائیں گے...بعض نے کہا ہے کہ اللہ کی صفت المومن کے معنی ہیں جو اپنے بندوں سے کئے
ہوئے وعدے سچ کر دکھائے.جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا ، مومن وہ ہیں جو کامل ایمان
والے ہیں.تمام انبیاء پر ایمان لانے والے ہیں اور یہ تمام انبیاء پر ایمان لانے کی ہدایت اللہ
تعالیٰ نے ہمیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے دی.ابوالعباس کے اس اقتباس
نے اسے مزید کھولا ہے لیکن جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ ایک احمدی جو دراصل تمام انبیاء کی
تصدیق کرنے والا ہے، ان کو ماننے والا ہے.وہی ہے جو حقیقی رنگ میں مومن ہے.641
Page 650
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ ٹھہرایا گیا ہے پہلے انبیاء پر بھی اور بعد میں آنے والے پر بھی.حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ : اللہ جل شانہ نے اسلامی امت کے
گل لوگوں کے لئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہد ٹھہرایا ہے اور فرمایاانَّا اَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ
رَسُوْلًا شَاهِدًا عَلَيْكُمُ (المزمل (16) اور فرمایا وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا
(النساء 42) مگر ظاہر ہے کہ ظاہری طور پر تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم صرف تئیس برس
تک اپنی امت میں رہے، پھر یہ سوال کہ دائمی طور پر وہ اپنی اُمت کے لئے کیونکر شاہد ٹھہر سکتے
ہیں یہی واقعی جواب رکھتا ہے کہ بطور استخلاف کے یعنی موسیٰ عالی سلام کی مانند خدا تعالیٰ نے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بھی قیامت تک خلیفے مقرر کر دئیے اور خلیفوں کی شہادت
بعینہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت متصور ہوئی....غرض شہادتِ دائمی کا عقیدہ جو
نص قرآنی سے بتواتر ثابت اور تمام مسلمانوں کے نزدیک مسلم ہے تبھی معقولی اور تحقیقی طور پر
ثابت ہوتا ہے جب خلافت دائمی کو قبول کیا جائے“.شہادت القرآن - روحانی خزائن جلد 6 صفحہ 363)
پس ہم احمدی اس ایمان پر قائم ہیں، ایک تو آخرت میں تصدیق ہوئی ہے جو ایمان بالغیب
پر یقین کرتے ہوئے ہوتی ہے.دوسرے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے زمانے کی
تصدیق بھی آنے والے کو ماننے پر ہونی ہے جو خاتم الخلفاء ہے.یہ مہر ہے جو کامل الایمان پر
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی لگے گی.احمدی کی تصدیق اس اعزاز کے ساتھ ہوگی کہ
ہاں اس نے پہلوں کو بھی مانا اور بعد میں آنے والوں کو بھی مانا.حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
ایک شخص آیا تھا.اس نے کچھ کہا تھا تو آپ نے فرمایا بس کر اب تو میں اپنی ہی امت پر
گواہی دینے کے قابل ہو گیا ہوں.مجھے فکر ہے کہ میری امت کو میری گواہی کی وجہ سے سزا
ملے گی“.الحكم جلد 7 نمبر 9 مورخہ 10 مارچ 1903ء)
642
Page 651
گواہی کی وجہ سے کیوں سزا ملے گی؟ اس لئے کہ ایمان لانے کا دعویٰ کرنے کے بعد بھی پھر
جو مصدق اعظم ہیں، اللہ تعالیٰ نے جس کی تصدیق کا اختیار دیا ہے ان کے عاشق صادق کو نہیں مانا.پس یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق پہلوں اور آخرین دونوں کے لئے ہے.اور پھر جو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی صفت مومن کے معنی ہیں کہ جو مومنوں سے اپنے کئے ہوئے
وعدے سچ کر دکھائے تو یہ وعدے بھی آج اُس خلافت کی تصدیق کی وجہ سے ہیں جو جماعت
احمدیہ سے ہی اللہ تعالیٰ پورے فرما رہا ہے.کیا مسلمانوں کے دوسرے فرقوں کو دین کی تمکنت
حاصل ہے؟ منہ سے بے شک ڈھٹائی سے کہتے رہیں جو چاہے کہیں لیکن صورتحال ہر ایک
کے سامنے ہے.پھر امام راغب اپنی لغت مفردات امام راغب میں لکھتے ہیں کہ الْمُؤْمِن کے اصل معنی
ہیں طمانیت نفس حاصل ہونا اور خوف کا زائل ہونا.پھر لکھتے ہیں کہ آمین،امن پانے والا ، بعض کے نزدیک اس سے مراد ہے اللہ کے حکم کے
مطابق امن پانے والا اور اس لحاظ سے وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا (آل عمران 98) کا معنی ہوگا کہ
جو شخص حرم میں داخل ہو جائے نہ اس سے قصاص لیا جاتا ہے نہ اس کے
اندر قتل کیا جاتا ہے
سوائے اس کے کہ وہ حرم کی حدود سے باہر آ جائے.کہتے ہیں یہی مضمون ان آیات میں ہے.فرمایا أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا امِنًا (العنكبوت (68) کہ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم
نے ایک امن والا حرم بنایا ہے.یہ معنی جو انہوں نے کئے ہیں اس سے بھی بہت وسیع معنی
ہیں.یہ اعلان اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھلا اعلان ہے اور اس بات کا ثبوت ہے کہ خانہ کعبہ اللہ کا
گھر ہے.جو بھی مسلمانوں کے حالات ہوئے یا ہیں، اللہ تعالیٰ نے ابھی تک ان کو تو فیق دی
ہے کہ اس کے تقدس کو قائم رکھیں بلکہ اصل میں تو کہنا یہ چاہئے کہ یہ تقدس اللہ تعالیٰ نے خود قائم
کیا ہوا ہے.اسلام سے پہلے بھی اس کا تقدس تھا.عربوں کی جہالت کے زمانے میں بھی اس
کی حیثیت حرم کی تھی اور امن کا نشان سمجھا جاتا تھا جبکہ ارد گرد کے ماحول میں اُس جہالت کے
643
Page 652
دور میں کسی بھی قسم کے امن کی ضمانت نہیں تھی.اللہ تعالیٰ کے اس امن والے گھر کی حفاظت بھی
خدا تعالیٰ نے ہمیشہ خود فرمائی ہے.قرآن کریم میں وہ واقعہ درج ہے جس میں اصحاب فیل
سے محفوظ رکھا تھا.اس لشکر کے سامنے اس وقت اہل مکہ کی کوئی حیثیت نہ تھی.لیکن اللہ تعالیٰ
نے اس کی حفاظت فرمائی.دنیا کو یہ بتا دیا کہ یہ امن والا گھر میراگھر ہے.اس کو دنیا کے امن
کے نشان کے طور پر میں نے بنایا ہے.اس کی طرف جو بھی ٹیڑھی نظر سے دیکھے گا اس کی اپنی
سلامتی اور امن کی کوئی ضمانت نہیں ہوگی.پھر یہ دوسری آیت کی مثال دیتے ہیں کہ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَآمَنَّا.وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيْمَ مُصَلَّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ أَن طَهَّرَا بَيْتِيَ
لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ (البقرة 126) اور جب ہم نے اپنے گھر کولوگوں
کے بار بار اکٹھا ہونے کی اور امن کی جگہ بنایا اور ابراہیم کے مقام میں سے نماز کی جگہ پکڑو اور ہم
نے ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید کی کہ تم دونوں میرے گھر کے طواف کرنے والوں اور اعتکاف
بیٹھنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لئے خوب گھر کو پاک صاف بناؤ.حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لفظ آمنا کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں
وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَآمَنَّا که آمنا، یہ مقام امن والا ہوگا.اس کے
ایک معنے یہ ہیں یعنی اسے دوسروں سے ہمیشہ محفوظ رکھا جائے گا.دوسرے معنے یہ ہیں کہ یہ مقام
دوسروں کو امن دینے والا ہوگا اور چونکہ حقیقی امن اطمینان قلب سے حاصل ہوتا ہے.اس لئے
آمنا کے تیسرے معنے یہ بھی ہیں کہ اطمینان قلب بخشنے والا.امن کے ذکر کے بعد اس آیت میں مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّی کا جوذ کر آیا ہے اس لئے کہ
اے مسلمانو! یہ لوگوں کے امن کی ضمانت بھی ہے اور ابراہیمی قربانیوں اور عبادتوں میں اس کا
امن چھپا ہوا ہے.اس پر عمل کر کے ہی تم امن حاصل کر سکتے ہو.حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تم
644
Page 653
اپنی نماز گاہ ابراہیم کے قدموں کی جگہ بناؤ.یعنی کامل پیروی کرو تا نجات پاؤ“.پھر فرمایا
یہ ابراہیم جوبھیجا گیا تم اپنی عبادتوں اور عقیدوں کو اس کی طرز پر بجالاؤ اور ہر ایک امر میں اس
کے نمونے پر اپنے تئیں بناؤ.پھر فرمایا کہ آیت وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى
اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ جب امت محمدیہ میں بہت فرقے ہو جائیں گے تب آخر زمانہ میں
ایک ابراہیم پیدا ہو گا اور ان سب فرقوں میں وہ فرقہ نجات پائے گا کہ اس ابراہیم کا پیر و ہوگا.( اربعین نمبر 3، روحانی خزائن جلد نمبر 17 صفحہ 421-420)
پس امن کی یہ ضمانت اس گھر سے منسوب ہونے والے کے لئے تب ہے جب عبادت
کے بھی وہ رُخ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں، جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے.اور اللہ تعالیٰ اس
زمانے میں کیا چاہتا ہے.اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کی تصدیق کرنے والا ہے اور ان کو امن
دینے والا ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کی پیروی کرنے والے ہیں.پس احمدی کو چاہئے کہ اپنی دعاؤں میں اس امن والے گھر کو بھی ہمیشہ اس لحاظ سے پیش نظر
رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ پہلا گھر جو امن و سلامتی کا نشان ہے جس میں آج احمدی کو داخل ہونے کی
اجازت نہیں ہے، احمدی کے لئے وہاں داخل ہونے میں امن کی کوئی ضمانت نہیں ہے جو اُس
ابراہیم کے پیرو ہیں جو سب سے زیادہ اس بات کا حقدار ہے کہ اس کے امن والے گھر میں
داخل ہو، اللہ تعالیٰ ایسے سامان پیدا فرمائے کہ مسیح محمدی اور اس زمانے کے ابراہیم کے
ماننے والے امن وسکون سے اس امن والے گھر میں داخل ہوسکیں اور جب وہ وقت آئے گا اور
انشاء اللہ ضرور آئے گا تو پھر دنیا دیکھے گی اور تسلیم کرے گی کہ ہاں اب اس کے حقیقی وارث اس
تک پہنچے ہیں اور اب اس امن کے سمبل (Symbol) کا اثر بھی دنیا میں پیار، محبت اور امن و
سلامتی کی صورت میں ظاہر ہورہا ہے.اس کا نقشہ خود امام راغب بھی پیش کر رہے ہیں.مسیح کی حدیث کے بارے میں کہتے ہیں
که نیز نزول مسیح کی حدیث میں بھی یہی الفاظ ہیں کہ تَقَعُ الْآمَنَةُ فِي الْأَرْضِ یعنی زمین پر مسیح
کے آنے سے امن و امان قائم ہو جائے گا.پس یہ امن اس مسیح سے وابستہ ہے جو آ چکا ہے اور
645
Page 654
جس نے جنگ اور قتال کے خلاف آواز اٹھائی ہے.اب اس کی آواز کو سن کر بھی مسلمان نہ
سمجھیں اور اس انتظار میں بیٹھے رہیں تو ان کی بدقسمتی ہے.جو یہ تشریح کرتے ہیں کہ مسیح کے
آنے کے بعد اس نے کیا کرنا ہے.اگر اس کو دیکھیں گے تو اُس مسیح نے کیا امن قائم کرنا ہے
جوان کے نظریہ کے مطابق آئے گا.اس نے تو طاقت سے صلیب کو بھی توڑنا ہے، اس نے تو
قتل وغارت بھی کرنی ہے.کیا قتل وغارت سے دنیا کے امن قائم ہوتے ہیں.پھر وہ کہتے ہیں کہ امن دو معنوں میں آتا ہے ایک معنی یہ ہیں کہ کسی کے لئے امن مہیا کرنا
اور اس معنی میں اللہ تعالیٰ کو مومن کہا جاتا ہے، یعنی امن عطا کرنے والا.اور امن کے دوسرے
معنی ہیں.خود امن میں آ گیا.اسے طمانیت نصیب ہوگئی.الایمان یہ لفظ تو کبھی اس شریعت
کے لئے استعمال ہوتا ہے جو حضرت محمد مصطفی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں.جیسا کہ
الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّبِئُونَ (المائدة (70).اور مومن اس معنی کے لحاظ سے ہر
اس شخص کو کہا جائے گا جو اللہ کی ہستی اور محمدصلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا اقرار کرتے
ہوئے اس کے دائرے میں داخل ہوتا ہے اور کبھی ایمان کا لفظ بطور مدح کے استعمال ہوتا
ہے.تب ایمان سے مراد ہوتا ہے اپنے نفس کو اس طرح حق کا مطیع بنادینا کہ حق کی تصدیق
کرتا ہو.جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس کی تفسیر میں روح المعانی میں مومن کے لفظ کے تحت
لکھا ہے کہ اپنی اور اپنے رسولوں کی اس بارے میں تصدیق کرنے والا کہ انہوں نے اس کی
طرف سے، یعنی اللہ کی طرف سے جو پیغام پہنچایا ہے وہ درست ہے، خواہ وہ یہ تصدیق اپنے
قول سے کرے یا معجزات دکھانے سے کرے.حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس آیت کی وضاحت میں مومن کی تفسیر کرتے
ہوئے فرماتے ہیں: ” خدا امن کا بخشنے والا اور اپنے کمالات اور توحید پر دلائل قائم کرنے والا
ہے.یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بچے خدا کا ماننے والا کسی مجلس میں شرمندہ نہیں ہوسکتا
اور نہ خدا کے سامنے شرمندہ ہوگا کیونکہ اس کے پاس زبردست دلائل ہوتے ہیں.لیکن بناوٹی
646
Page 655
خدا کا ماننے والا بڑی مصیبت میں ہوتا ہے.وہ بجائے دلائل بیان کرنے کے ہر ایک بیہودہ
بات کو راز میں داخل کرتا ہے تاہنسی نہ ہو اور ثابت شدہ غلطیوں کو چھپانا چاہتا ہے“.اسلامی اصول کی فلاسفی، روحانی خزائن جلد 10 صفحه 375)
پس یہ ہے امن بخشنے والا خدا جس پر ایمان کی مضبوطی اسے ہر مخالف کے مقابل پر جرات دلاتی
ہے.روح المعانی میں مومن کے لفظ کی مزید وضاحت میں لکھا ہے کہ المومن کا معنی ہے وہ جو اپنے
بندوں کوسب سے بڑی گھبراہٹ یعنی قیامت کے دن سے امن بخشنے والا ہے.پھر بندوں کو اس
سب سے بڑی گھبراہٹ سے اس طرح امن بخشنے والا ہے کہ ان کے دلوں میں طمانیت پیدا کر دے
یا انہیں اپنی جناب سے خبر دے کر امن بخشے کہ ان پر کوئی خوف نہ ہوگا.ثعلب نے بیان کیا ہے کہ المومن کا معنی مصدق ہے اور اللہ تعالیٰ مومنوں کے دعوی
ایمان کی تصدیق کرنے والا ہے.بعض نے المومن کا معنی کیا ہے وہ جو کہ زوال کے عیب
سے خود امن میں ہے کہ خدا تعالیٰ پر کسی قسم کا زوال آنا محال ہے.پس یہ ہیں لفظ مومن کے چند معانی جو اللہ تعالیٰ کی ذات میں استعمال ہوتے ہیں.اللہ تعالیٰ
امن دینے والا بھی ہے، امن میں رکھنے والا بھی ہے اور ایمانوں کو مضبوط کرنے والا بھی ہے.اس لئے ہر احمدی کو کوشش کرنی چاہئے کہ اس اللہ تعالیٰ کی ہر صفت پر اپنے کامل ایمان کے
ساتھ عمل کرنے والے ہوں.خطبہ جمعہ حضرت خلیفہ امسیح الخامس اید والله، فرمودہ 06 جولائی 2007ء - خطبات مسر در جلد پنجم صفحہ 279تا285)
(
647
Page 657
بِسْمِ
سورة الاعلى
اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 1 - ( میں ) اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا
سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى
الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى
وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى
( اور ) بار بار رحم کرنے والا ہے ( پڑھتا ہوں )
2.(اے رسول ) ! اپنے بزرگ ( و برتر ) ربّ
کے نام کا بے عیب ہو نا بیان کر.3.(وہ) جس نے (انسان کو ) پیدا کیا اور (اسے)
بے عیب بنایا.4.اور جس نے ( اس کی طاقتوں کا اندازہ کیا اور
ان کے مطابق ) اسے ہدایت دی.وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى
5.اور جس نے زمین سے چارہ نکالا.فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى
6.پھر اسے سیاہ کوڑا کرکٹ بنا دیا.سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى
7.(اے مسلمان ) ہم تجھے (اس طرح) پڑھائیں
گے کہ اس کے نتیجہ میں تو بھولے گا نہیں.إِلَّا مَا شَاءَ اللهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ 8.سوائے اس کے جو اللہ بھلانا چاہے.وہ یقیناً
وَمَا يَخْفى
وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى
فَذَكِّرُ انُ نَفَعَتِ الذِّكْرُى
سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشُى
ظاہر کو بھی جانتا ہے اور اسے بھی جو مخفی ہے.9.اور ہم (اے مسلمان ) تیرے لئے ( کامیابیوں
اور ) آسانیوں کا حصول آسان کر دیں گے.10.پس تم بھی نصیحت کرو.نصیحت کرنا ( ہمیشہ دنیا
میں ) مفید ہوتا رہا ہے.11.جو( خدا سے ) ڈرتا ہے وہ یقیناً نصیحت حاصل
کرے گا.649
Page 658
وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى
الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى &
12.اور اس کے برخلاف) جو نہایت بدبخت
ہوگا وہ اس سے گریز ہی کرتا رہے گا.13 - ( وی ) جو بڑی آگ میں داخل ہونے والا ہے.ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيي 14.پھر اس میں داخل ہونے کے بعد ) نہ تو وہ
قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى
وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى
بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَوةَ الدُّنْيَات
وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى
إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولى
صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى ®
اس میں مرے گا اور نہ زندہ رہے گا.15.جو پاک بنے گا وہ یقیناً کامیاب ہوگا.16.بشرطیکہ (پاک بننے کے ساتھ ساتھ ) اس
نے اپنے رب کا نام بھی لیا اور نماز پڑھتا رہا.17.مگر (اے مخالفو ) ! تم (لوگ) تو ورلی
زندگی کو ( آخرت پر ) ترجیح دیتے ہو.18 - حالانکہ آخرت کہیں بہتر اور دیر پا ہے.19.یقیناً یہی (بات) پہلے صحیفوں میں بھی ( درج ) ہے.20.( یعنی ) ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں.650
Page 659
قَد أَفْلَحَ مَن تَزَفى
حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں:
فلاح وہ شخص پاوے گا جو اپنے نفس میں پوری پاکیزگی اور تقویٰ طہارت پیدا کر لے اور
گناہ اور معاصی کے ارتکاب کا کبھی بھی اس میں دورہ نہ ہو اور ترک شر اور کسب خیر کے دونوں
مراتب پورے طور سے یہ شخص طے کر لے تب جا کر کہیں اسے فلاح نصیب ہوتی ہے.ایمان
کوئی آسان سی بات نہیں.جب تک انسان مربی نہ جاوے جب تک کہاں ہوسکتا ہے کہ سچا
ایمان حاصل ہو.الحکم جلد 12 نمبر 32 مورخہ 10 مئی 1908 صفحہ 3)
حضرت خلیفہ المسیح الاول رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:
سبح اسم ربك الأعلى.اسيح : پاکی بیان کر.شرک وغیرہ کے عیوب سے اس کی تنزیہ کر.آیت شریف میں
اللہ تعالیٰ کی تین صفات کا ذکر ہے.سٹوحیت.ربوبیت.علو شان.اس کے ماتحت پیغمبر
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے تین پیشگوئیاں تھیں جو بڑی صفائی سے پوری ہوئیں.آپ
جنون، افتراء وغیرہ عیوب سے پاک تسلیم کئے گئے.آپ کی ربوبیت مگی زندگی کی ادنی
حالت سے يَوْمًا فَيَوْمًا بڑھتی گئی اور اعلیٰ ترین مقام پر یہاں تک پہنچائی گئی کہ
وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللهِ أَفْوَاجًا - النصر (3) اور أَثْمَمتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي
(المائدۃ4) کی آواز آپ نے سن لی.روئے سخن
پیغمبرصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہے.مگر مفہوم کے اعتبار سے ہر صادق راست باز کے لئے عام مخاطبت ہے.ضمیمه اخبار بدر قادیان 4 جولائی 1912ء)
651
Page 660
الَّذِي خَلَقَ فَسَوَى وَالَّذِي قَدَّدَ فَهَدَى.خلق: تسویه تقدیر.اور ہدایت.ان چار باتوں کو علی الترتیب علت اور معلول کے
سلسلہ میں بیان فرما کر حصول ترقی کے لئے راہ سمجھائی ہے.روئے سخن صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کی
طرف ہے اور مفہوم کے اعتبار سے ہر ترقی کے خواہاں کے لئے اس میں ہدایت ہے.(ضمیمه اخبار بدر قادیان 4 جولائی 1912ء)
آیت الَّذِی خَلَقَ فَسَوی میں آریہ کا رڈ ہے جو خُلق عالم کا منکر ہے اور سمجھتا ہے کہ
اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا.اس مضمون کو بلفظ دیگر قرآن شریف میں یوں ادا فرمایا
ہے.الَّذِي أعْطى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى (طه 51)
(ضمیمه اخبار بدر قادیان 4 جولائی 1912ء)
وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى فَجَعَلَهُ عُمَّاءَ أَحْوَى.مرغی : زمینی گھاس پات.سبز.مُقآء خشک کوڑا کرکٹ.محقآء جمع ہے.اس کا
واحد مخفاة آیا کرتا ہے.آخوی حوة سے مشتق ہے.سبزی کے بعد کسی چیز کا سیاہ ہو جانا
محوۃ ہے.پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے مقابلہ میں کفار کا جو انجام ہونے
والا تھا ان دو آیتوں میں دکھلایا ہے جو خس کم جہاں پاک کے مصداق ہو گئے.روئے سخن
ابوجہل، عتبہ، شیبہ، ربیعہ وغیرہ اس وقت کے کفار کی طرف ہے.مگر مفہوم کے اعتبار سے
مصداق اس کے ہر صادق، راستباز کے معاند ہیں.انہیں کا وجود ان کے کھیت کے لئے کھاد
بن جاتا ہے.ضمیمه اخبار بدر قادیان 4 / جولائی 1912ء)
سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى
حدیث شریف میں آیا ہے کہ قرآن شریف جسے یاد ہے وہ اس کو پڑھتا پڑھاتا
رہے.اگر پڑھنے میں ڈھیل دے دی گئی تو وہ گھلے ہوئے اونٹ سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ
سینوں سے نکل جاتا ہے.پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے ہر
652
Page 661
،،
سال ایک بار دور کیا کرتے تھے.سالِ وفات آپ نے دوبار دور کیا.”س“ کے معنے ضرور
بالضرور کے ہیں.إِلَّا مَا شَاء الله کے تحت میں موجود قرآن شریف کے علاوہ جس قدر مختلف
قراء تیں عرب کے لب ولہجہ کی وجہ سے تھیں سب نسيا منسيا ہو گئیں.جو زیادہ تر مشہور
قراءت تھی وہی متلور ہی.قرآن شریف کے جمع کے متعلق صحابہ رضی اللہ عنہ کا فعل تھا.شیعہ
معترضین اس پر غور فرماویں.ان آیات میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے سلسلہ میں بتایا کہ ہم تجھے
پڑھائیں گے اور تو کبھی نہیں بھولے گا.جیسے پہلی آیتوں میں بتایا تھا کہ ہر شے کو اللہ تعالیٰ
نے ایسے فطرتی قومی دیئے ہیں جو اس کی تکمیل کے لئے ضروری ہیں.ایسا ہی اس کو اس کے
کمال مطلوبہ تک پہنچنے کا طریق بتایا ہے.پس جس بانجود ہستی کو نور نبوت دیا جاتا ہے ضرور ہے
کہ اس کے قویٰ میں بھی وہی قوت اور طاقت ہو اور اس بار نبوت کے اٹھانے کے لئے وہ
ہمہ تن تیار ہو.اور ہر قسم کی مشکلات جو اس راہ میں پیش آویں ان کے برداشت کرنے کا حوصلہ
اور استقلال اس میں موجود ہے.پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بشارت دی جاتی
ہے کہ تیرے آنے کی جو غرض دنیا میں ہے اس کے حسب حال آپ کو قومی دیتے ہیں اور اس
کی تکمیل کی جو راہ ہے وہ آپ کو بتادی جاتی ہے.اگر یہ سوال ہو کہ یہ علوم جو نبوت کے متعلق
ہیں وہ کس طرح پر محفوظ رہیں گے اور آپ کس طرح پڑھ لیں گے.تو سُنو ! اس کے متعلق ہم
پیشگوئی کرتے ہیں.سنفر نك فلا تنسی.ہم مجھ کو پڑھا دیں گے اور تو کبھی نہیں بھولے
گا.اب جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ اور بشارت دی تھی کہ تو ہمارے پڑھائے ہوئے علوم کبھی
نہیں بھولے گا.اس وعدہ کے موافق اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو
قرآن مجید پڑھایا اور تمام اسرار و حقائق و معارف و دقائق آپ پر منکشف کئے.علوم اولین و
آخرین عطا فرمائے.اور اس پر بھی ربّ زِدْنِي عِلْمًا ( طه 115) کی دعا سکھائی.اس آیت میں یہ بھی بتایا ہے کہ بھولے گا نہیں.مگر إِلَّا مَا شَاءَ اللہ بھی اس کے ساتھ
653
Page 662
ہے.اب غور طلب بات یہ ہے کہ اس سے کیا مراد ہے؟ سویا درکھنا چاہئے کہ ضروریاتِ دین
اور کلام ربانی جس کا دنیا کو پہنچانا مقصود ہے وہ تو کبھی آپ کو بھول ہی نہیں سکتا اور نہ ایسا ہوسکتا
ہے کیونکہ اگر ایسا ہو تو پھر آمان ہی اُٹھ جاوے.قرآن مجید خود اس کی تشریح دوسری جگہ کرتا
ہے.ایک جگہ فرماتا ہے.لَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ(بنی اسرائیل87)
یعنی اگر ہم چاہتے تو جو کچھ تیری طرف وحی کیا ہے اسے لے جاتے.مگر ایسا وقوع میں نہیں آیا.اس لئے إِلَّا مَا شَاءَ اللهُ یا لَئِن شئنا سے یہ مراد نہیں ہو سکتا کہ ایسا وقوع میں بھی آیا.اور اگر
آیا بھی تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا کوئی قرآن کریم میں اس کا پتہ ہے.اس لئے ایک جگہ فرمایا.فَيَنْسَخُ اللهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَنُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللهُ ايَتِهِ (الحج 53) یعنی شیطانی القاء کو اللہ تعالی مٹا
دیتا ہے.اور اپنی آیات کو مضبوط کرتا ہے.اور ایک اور جگہ فرمایا.يَنحُ اللهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُ
الْحَقِّ بِكَلِمَاتِه (الشوری25) اللہ تعالیٰ باطل کو محو کر دیتا ہے اور اپنے کلماتِ حق کو حق ثابت
کرتا ہے.پس معلوم ہوا إِلَّا مَا شَاءَ اللہ سے اگر کوئی مراد ہے تو وہ باطل اور ارادہ و تدابیر
شیطانی ہیں جو آپ کی مخالفت کے لئے کی جاتی تھیں.یہ بھی گویا عظیم الشان پیشگوئی ہے.اس
کو واقعات سے ملا کر دیکھو کہ کس طرح پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پڑھایا گیا وہ قائم
رہا.اور دنیا اس کو نہیں بھول سکتی.قرآن کریم کی وحی آج تک بھی اسی قوت وشان کے ساتھ
زندہ اور محفوظ ہے.پھر اس کو مؤشید کرنے کے لئے فرمایا إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى
( الا علی(8) یعنی یہ اس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہے جو ظاہر اور مخفی تمام امور کا پورا علیم وخبیر
ہے.پس یہ بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کی دلیل ہے.اس کے بعد ایک اور دلیل برنگ پیشگوئی فرمائی کہ وَنُيَشِرُكَ لِلْيُسْرَى یعنی تیرے ہر
ایک کام میں سہولتیں اور آسانیاں پیدا کی جائیں گی.مگی زندگی جس محسر اور تنگی کی زندگی تھی وہ
تاریخی اوراق سے عیاں ہے لیکن بعد میں آپ کے لئے جس قدر سہولتیں پیدا ہوئی ہیں وہ بھی
ایک ظاہر امر ہے.ہر کام میں سہولت اور آسانی پیدا ہوگئی اور اس طرح پر یہ پیشگوئی پوری
ہوئی.اس کے بعد پھر ایک پیشگوئی فرمائی کہ آپ کا کام تذکیر ہے.آپ اس نصیحت کو
654
Page 663
لوگوں تک پہنچاتے جائیں.یہ خالی از فائدہ نہ ہوگی.ضرور اپنا مفید نتیجہ پیدا کرے گی.ضمیمه اخبار بدر قادیان 4 جولائی 1912ء)
وَنُيَسِرُكَ لِلْيُسْرَى
مگی زندگی آپ کی جس قسم کی عسرت کی تھی.اس کو پیش نظر رکھ کر آپ کے عروج اور
کمال تک نظر کی جاوے تو آیت کا مفہوم خوب سمجھ میں آجاتا ہے.علاوہ اس کے یہ بھی معنے ہیں
کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین لائے ہیں اس کی تعریف آپ نے یوں فرمائی ہے.مَا بُعِثْتُ بِالْيَهُودِيَّةِ وَلَا بِالنَّصْرَانِيَّةِ وَلَكِن بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّيْحِيَّةِ...یعنی افراط و
تفریط اور رہبانیت سے منزہ سہل اور آسان دین کے ساتھ آپ مبعوث ہوئے.سفر میں قصر
ہے.عذر ہو تو تیم ہے.مسجد نہ ہو تو سب جگہ مسجد ہی مسجد ہے.قدير إن نَفَعَتِ الذكرى.( ضمیمه اخبار بدر قادیان 4 جولائی 1912 ء )
لان بمعنے قد ہے.جیسے فرما یا سُبحن رَبَّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبَّنَا لَمَفْعُولًا.(بنی اسرائیل
109) وَإِن كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ (آل عمران 165) ان کے معنے ہر جگہ شرطیہ نہیں
ہوتے.ان دو مقام کے علاوہ قرآن شریف میں کثرت سے ان قد کے معنوں میں آیا ہے.افَتَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِكرَ صَفْعًا أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِين (زخرف 6) سے معلوم ہوتا ہے کہ
کوئی سنے یانہ سنے.وعظ ونصیحت کبھی ترک نہیں کرنا چاہئے.گوش زدہ اثر ے دارد.( ضمیمه اخبار بدر قادیان 4 جولائی 1912ء)
قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ
الدُّنْيَا
فلاح کے لئے ظاہری و باطنی طہارت، پراگندہ خیالات سے دلجمعی.ذکر ونماز و با لآخر
دین کو دنیا پر مقدم کرنا.یہ باتیں ضروری ہیں.حضرت مسیح موعود کا ایک الہام ہے.مصفح قطره باید که تا گوہر شود پیدا ) آئینہ کمالات اسلام صفحہ 55 ) ایک ڈاکٹر صاحب
655
Page 664
نے جو ایم اے ہیں اعتراض کیا کہ موتی تو کیڑے کے لعاب سے پیدا ہوتا ہے.یہ حال کی
تحقیقات کا مشاہدہ ہے مگر جب ان کو توجہ دلائی گئی کہ سیپ میں کیڑا کس چیز سے پیدا ہوتا
ہے.تو چونکہ ڈاکٹر تھے خاموش ہو گئے.ایک اور الہام حضرت صاحب کا ہے جس کو تزکیۂ نفس
اور ذکر سے تعلق ہے وہ یہ ہے.إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ عُرِضَ عَلَى أَقْوَامٍ فَمَا دَخَلَ فِيْهِمْ وَمَا
دَخَلُوا فِيْهِ إِلَّا قَوْمُ مُّنْقَطِعُوْنَ.سبح اسم ربك الأعلى
ضمیمه اخبار بدر قادیان 4 / جولائی 1912ء)
آدمی کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے.اور اس کے لئے دو قسم کی چیزیں ضروری ہیں.ایک
جسم جو ہمیں نظر آتا ہے.اس کے لئے ہوا کی ضرورت ہے.کھانے، پینے، پہنے، مکان کی
ضرورت ہے.کوئی اس کا یار و غمگسار ہو.اس کی ضرورت ہے.دور دراز ملکوں کے دریاؤں
کے اس پار جانے کی ضرورت ہے.زمیندار کو کھیت کی ضرورت ہے.کیا زمین انسان بنا سکتا
ہے؟ پھر ہل کے لئے لکڑیاں چاہئیں.مضبوط درخت ہو جب جا کر ہل بنتے ہیں.ہل کے لئے
لوہے کی ضرورت ہے.پھر اوزار بھی لوہے کے ہوتے ہیں.لوہے کا بھی عجیب کارخانہ ہے.لوہا کانوں سے آتا ہے جس کے لئے کتنے ہی مزدوروں کی ضرورت ہے.پھر اور کئی قسم کی
محنتوں اور مردوں کے بعد ہل بنتا ہے.مگر یہ بل بھی بیکار ہے جب تک جانور نہ ہوں.پھر
جانوروں کے لئے گھاس چارہ وغیرہ کی ضرورت ہے.پھر اس ہل چلانے میں علم فہم اور
عاقبت اندیشی کی ضرورت ہے.چنانچہ انہی کی مدد سے چھوٹے چھوٹے جتنے پیشے بنتے ہیں وہ
عالی شان بنتے ہیں.مثلاً چگی پینا ایک ذلیل کسب تھا.علم کے ذریعہ ایک اعلیٰ پیشہ ہو گیا.یہ جو بڑے بڑے
میلوں کے کارخانے والے ہیں دراصل چگی پینے کا ہی کسب ہے.اور کیا ہے؟ ایسا ہی گاڑی
چلانا.کیا معمولی کسب تھا.گاڑی چلانے والا ہندوستان میں لنگوٹ باندھے ہوتا تھا.اب
گاڑی چلانے والے کیسے عظیم الشان لوگ ہیں.یہ بھی علم ہی کی برکت ہے.656
Page 665
حجام کا پیشہ کیسا ادنی سمجھا جاتا.یہی لوگ مرہم پٹی کرتے اور ہڈیاں بھی درست کر دیتے.اسی پیشے کو علم کے ذریعے ترقی دیتے دیتے سر جنی تک نوبت پہنچ گئی ہے.اور سرجن بڑی عزت
سے دیکھا جاتا ہے.میں نے تاجروں پر وہ وقت بھی دیکھا ہے کہ سر پر بوجھ اٹھائے وہ در بدر پھر رہے ہیں.رات کسی مسجد میں کاٹتے ہیں مگر اب تو تجارت والوں کے علیحدہ جہاز چلتے ہیں.وہ حکومت بھی دیکھی ہے کہ دس روپے لینے ہیں اور ایک زمیندار سے دھینگا مشتی ہورہی
ہے یا اب منی آرڈر کے ذریعہ مالیہ ادا کرتے ہیں.سنسان ویران جنگلوں کو آباد کر دیا گیا ہے.یہ بھی علم ہی کی برکت ہے کہ اس سے ادنی چیز اعلیٰ ہو جاتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس جسم کے
علاوہ کچھ اور بھی عطا کیا ہے.یہ آنکھیں نہیں دیکھتیں جب تک اندر آ نکھ نہ ہو.زبان نہیں بولتی
جب تک اندر زبان نہ ہو.کان نہیں سنتے جب تک اندر کان نہ ہوں.مگر یہ تو کافر کو بھی حاصل
ہے.اس کے علاوہ ایک اور آنکھ وزبان وکان بھی ہے جو مومن کو دئیے جاتے ہیں.یہ وہ آنکھ
ہے جس سے انسان حق و باطل میں تمیز کر سکتا ہے.حق و باطل کا شنوا ہوسکتا ہے.حق و باطل کا
اظہار کر سکتا ہے.اگر انسان حق کا گویا وشنو و بینا نہ ہو تو م بكم غمی کا فتویٰ لگتا ہے.اللہ جلشانہ جس کو آنکھ دیتا ہے وہ ایسی آنکھ ہوتی ہے کہ اس سے خدا کی رضا کی راہوں کو
دیکھ لیتا ہے.پھر ایک آنکھ اس سے بھی تیز ہے جس سے مومن اللہ کی راہ پر علی وجہ البصیرت
چلتے ہیں.پھر اس سے بھی زیادہ تیز آنکھ جو اولوالعزم رسولوں کو دی جاتی ہے.ان حواس کے
متعلق اللہ اپنے پاک کلام میں وعظ کرتا ہے.دیکھو آج (جمعہ کا دن ) لوگوں نے کچھ نہ کچھ
اہتمام ضرور کیا ہے.غسل کیا ہے.لباس حتی المقدور عمدہ ونیا پہنا ہے.خوشبولگائی ہے.پگڑی
سنوار کر باندھی ہے.یہ سب کچھ کیوں کیا.صرف اس لئے ہم باہر بے عیب ہو کر نکلیں.بہت
سے گھر ایسے ہوں گے جہاں بیوی بچوں میں اسی لئے جھگڑا بھی پڑا ہوگا.اور اس جھگڑے کی اصل
بناء یہی ہے کہ بے عیب بن کر باہر نکلیں.657
Page 666
جس طرح فطرت کا یہ تقاضا ہے اور انسان اسے بہر حال پورا کرتا ہے.اسی طرح اللہ تعالیٰ
فرماتا ہے کہ میں تمہارا مربی، میں تمہارا محسن ہوں جیسے تم نے اپنے جسم کو مصفی و مطہر
بے عیب بنا کر نکلنے کی کوشش کی ہے.ویسے ہی تم اپنے رب کے نام کی بھی تسبیح کرتے
ہوئے نکلو اور دنیا والوں پر اس کا بے عیب ہونا ظاہر کرو.ادنی مرتبہ تو یہ ہے کہ مومن اپنی زبان
سے کہے.سُبحان اللهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ
پھر وہ کلمات جن سے میں نے اپنے خطبہ کی ابتدا کی اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ
وَاللهُ أَكْبَرُ.وَلِلهِ الْحَمدُ.اس میں بھی اس کی کبریائی کا بیان ہے.پھر اس سے ایک اعلیٰ مرتبہ
ہے.وہ یہ ک تسبیح دل سے ہو کیونکہ یہ جناب الہی کے قرب کا موجب ہے.كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ سُبْحَانَ اللهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ اور فرماتا
ہے کہ ولكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ (الحج 38) پس ضرور ہے کہ یہ تسبیح جو کریں تو دل کو
مصفا کر کے کریں.تیسرا درجہ یہ ہے کہ اللہ کے فضل پر ناراض نہ ہوں اور یہ یقین کریں کہ جو کچھ خدا کرتا ہے
بھلا ہی کرتا ہے.اور جو کچھ کرے گا وہ بھی ہماری بھلائی و بہتری کے لئے کرے گا.پس ہمیں چاہئے کہ اس اللہ کو جس کی ذات اعلیٰ اور تمام قسم کے نقصوں اور عیبوں سے بالاتر
ہے.رنج و راحت ، سر وئیسر میں بے عیب یقین کریں.غرض تم زبان سے سبحان اللہ کا ورد کرو تو اس کے ساتھ دل سے بھی ایسا اعتقاد کرو اور اپنے دل
کو تمام قسم کے گندے خیالات سے پاک کر دو.اگر کوئی تکلیف پہنچے تو سمجھو کہ مالک ہماری
اصلاح کے لئے ایسا کرتا ہے.پھر اس سے آگے اللہ توفیق دے تو اللہ کے اسماء پر، اللہ کے صفات و افعال پر، اللہ کی
کتاب پر، اللہ کے رسول پر جولوگ اعتراض کرتے ہیں اور عیب لگاتے ہیں ان کو دُور کرو اور
ان کا پاک ہونا بیان کرو.658
Page 667
پس میری سمجھ میں یہ وقت ہے کہ جہاں تک تم میں کسی سے ہو سکے اللہ کے اسماء ، صفات،
افعال، اللہ کی کتاب اللہ کے رسول اللہ کے رسول کے نواب و خلفاء کی پاکیزگی بیان کرے.اور ان پر جو اعتراض ہوتے ہیں انہیں بقدر اپنی طاقت کے سلامت روی وامن پسندی کے
ساتھ دُور کرنے کی کوشش کریں.یہ مت گمان کرو کہ ہم ادنی ہیں.وہ طاقت رکھتا ہے کہ تمہیں ادنیٰ سے اعلیٰ بنادے.چنانچہ
وہ فرماتا ہے خَلَقَ فَسَوَى وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى (الا على 3-4)
جوان پڑھ میں انہیں کم از کم یہی چاہئے کہ وہ اپنے چال و چلن سے خدا کی تنزیہ کریں.یعنی اپنے
طرز عمل سے دکھائیں کہ قدوس خدا کے بندے، پاک کتاب کے ماننے والے، پاک رسول کے
متبع اور اس کے خلفاء اور پھر خصوصا اس عظیم الشان مجدد کے پیر وایسے پاک ہوتے ہیں.( بدر 13 را کتوبر 1910 صفحہ 9،8)
ہر شخص پر جو قرآن پر ایمان لایا.جس نے محمد رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا.جو اللہ
پر ایمان لایا.اس کی کتابوں پر ایمان لایا.فرض ہے کہ وہ کوشش کرے کہ خدا تعالیٰ کے کسی
نام پر کوئی اعتراض نہ کرنے پائے.اگر کرے تو اس کا ذب کرے.اس لئے ارشاد ہوتا ہے.ستخ.جناب الہی کی تنزیہ کر.اس کی خوبیاں ، اس کے محامد بیان کر.میں نے بعض نادانوں کو دیکھا ہے.جب جناب الہی ، اپنی کامل حکمت و کمالیت سے
اس کے قصور کے بدلے سزا دیتے ہیں اور وہ سزا اسی کی شامت اعمال سے ہی ہوتی ہے.جیسے
فرما يا وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم (الشوری 31) تو وہ شکایت کرنے
لگ جاتے ہیں.مثلاً کسی کا کوئی پیارے سے پیارا مر جائے تو اس ارحم الراحمین کو ظالم کہتے
ہیں.بارش کم ہو تو زمیندار سخت لفظ بک دیتے ہیں.اور اگر بارش زیادہ ہو تو تب بھی خدا تعالیٰ
کی حکمتوں کو نہ سمجھتے ہوئے بُرا بھلا کہتے ہیں.اس لئے ہر آدمی پر حکم ہے کہ اللہ تعالی کی تنزیہ و
تقدیس وسیع کرے.آپ کے کسی اسم پر کوئی حملہ کرے تو اس حملہ کا دفاع کرے.اب میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں کوئی بُرا کہے یا تمہارے ماں باپ یا بھائی بہن یا محبوب
659
Page 668
کو سخت سست کہہ دے تو تمہیں بڑا بڑا جوش پیدا ہوتا ہے یہاں تک کہ مرنے مارنے پر تیار ہو
جاتے ہو لیکن جس وقت اللہ کے کسی فعل پر ( کہ وہ بھی اس کے اسم کا نتیجہ ہے ) کوئی نادان یا
شریر اعتراض کرتا ہے تو تم کہتے ہو.جانے دو.کافر ہے.بکتا ہے.اس وقت تمہیں جوش
نہیں.حالانکہ جن کے لئے تم نے اتنا جوش دکھایا ان میں تو کچھ نہ کچھ نقص یا عیب و قصور ضرور ہو
گا.مگر اللہ تو ہر برائی سے منزہ ہ، ہر حمد سے محمود ہے.ہر وقت تمہاری ربوبیت کرتا ہے.اب جو
اس کے اسماء کے لئے اپنے تئیں سینہ سپر نہیں کرتا وہ نمک حرام ہی ہے.اور کیا؟
بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم کوئی پڑھے ہوئے ہیں جولوگوں سے مباحثے کرتے پھریں ؟ تعجب کی
بات ہے کہ اگر کوئی ان کے ماں باپ یا بھائی بہن کو یا کسی دوست کو یا خودان کو بُرا کہہ دے تو
ناخواندگی یاد نہیں رہتی اور سنتے ہی آگ ہو جاتے ہیں.اور پھر جس طریق سے ممکن ہو اس کا دفاع
کرتے ہیں.مگر جناب الہی سے غافل ہیں.اسی طرح خدا کے برگزیدوں پر طعن کرنا دراصل خدا
تعالیٰ کی برگزیدگی پر طعن رکھنا ہے.اس کے لئے بھی مومنوں کو غیرت چاہئے.ایک شخص تمہارے پاس آتا ہے اور تم کو آ کر کہتا ہے.میاں تم بڑے اچھے، بڑے
ایمان دار.آئیے تشریف رکھئے.باپ تمہارا بڑا ڈوم، بھڑوا ، کنجر، بڑا حرام زادہ ، سو ر، ڈاکو،
بدمعاش تھا.تم بڑے اچھے آدمی ہو اور ساتھ ساتھ خاطر داری کرتا جائے تو کیا تم اس کے اخلاق
کی تعریف کرو گے؟
مومن کا فرض ہے کہ جناب الہی میں تسبیح کرے.اس کے اسماء کی تسبیح میں کوشاں رہے.ان
کے انتخاب شدہ بندوں کی تسبیح کرے.ان پر جو الزام لگائے جاتے ہیں، جو عیوب ان کی طرف شریر
منسوب کرتے ہیں.اُن کا دفاع وذب کرے اور سمجھائے کہ جنہیں میرارب برگزیدہ کرے، وہ بدکار
اور لعنتی نہیں ہوتے.ان کی تسبیح خدا کی تسبیح ہے.ی معنے ہیں سبح اسم ربک الاعلی کے.فَذَكِرانْ نَّفَعَتِ الذِكرُى
ہم تمہیں نصیحت کرتے ہیں اور اللہ فرماتا ہے نصیحت کرتے رہو.نصیحت ضرور سُودمند
660
Page 669
ہوتی ہے.میرا جی چاہتا ہے کہ تم باہر والوں کے لئے نمونہ بنو.تمہارا لین دین، تمہاری گفتار و
رفتار، تمہارا چال چلن ( تمہارا اسر، وعلن ) تمہارا اٹھنا بیٹھنا.تمہارا کھانا پینا ایسا ہو کہ دوسرے
لوگ بطور اُسوہ حسنہ اسے قرار دیں.تم اللہ کو علیم و خبیر و بصیر مان کر اپنے آپ کو بدیوں سے
رو کو.یہ بھی ایک قسم کی تسبیح ہے.تم ایسا کرو گے تو دوسرے لوگوں کا ایمان بھی بڑھے گا.(ماخوذ از حقائق الفرقان )
حضرت خلیفہ المسیح الثانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:
افضل 23 جنوری 1913 ، صفحہ 12-13)
سیخ امر کا صیغہ ہے اور سبح کے معنے ہوتے ہیں اُس نے اُسے نقص سے پاک
قرار دیا (اقرب) پس سیع کے معنے ہوئے نقص سے پاک قرار دے.رب کے معنے
ہوتے ہیں وہ ذات جو تدریجی طور پر ترقی دیتے ہوئے کمال تک پہنچاتی ہے.گویا پیدا کرنا اور
پھر تدریجی طور پر ترقی دیتے ہوئے کمال تک پہنچانا یہ سب کچھ رب کے مفہوم میں شامل ہے.سبح اسم ربک الاعلی کے معنے ہیں توسیع کر اپنے رب کے نام کی جو اعلیٰ ہے.یا اپنے رب
کے اعلی نام کی تسبیح کر.یہاں اعلی صفت رب بھی ہو سکتا ہے اور صفت اسم بھی.یعنی اپنے رب کے
اسم کی جو اعلی ہے تسبیح بیان کر.اور یہ معنے بھی ہوسکتے ہیں کہ اپنے اعلیٰ رب کے نام کی تسبیح بیان کر.رب کی صفت قرار دینے کی صورت میں اس کے یہ معنے ہوں گے کہ تیرا رب جو اعلیٰ ہے
یعنی تیرا رب جس کی ربوبیت سب سے بلند اور ارفع شان رکھتی ہے اُس کی تسبیح بیان کر.اور اسم
کی صفت ہونے کی صورت میں آیت کے یہ معنی ہوں گے کہ تو اپنے رب کے سب سے بلند نام
کی تسبیح بیان کر اور مطلب یہ ہوگا کہ تو اپنے رب کا نام دنیا میں بلند کر.پہلی کتابوں کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں کبھی اللہ تعالیٰ کو باپ کہ دیا جاتا.کبھی اسے ماں کہہ کر پکارا جاتا.کبھی کسی نبی کو خدا کا بیٹا کہہ دیا جاتا.کبھی کسی نبی کو خدا کا
اکلوتا قرار دے دیا جاتا ہے.اس کے یہ معنے نہیں تھے کہ اللہ تعالیٰ کے بھی بیٹے ہیں یا اللہ تعالیٰ
661
Page 670
بھی باپ اور ماں کی طرح ہے بلکہ صرف اس حقیقت کو ظاہر کرنے کے لئے کہ جس طرح بیٹا
باپ میں سے نکلتا ہے اسی طرح نبی خدا تعالی کی طرف سے اس کی صفات کو ظاہر کرنے کے
لئے کھڑا ہوتا ہے.تیشیبی کلام استعمال کیا گیا تھا اور دراصل ایسا ہونا ضروری بھی تھا.کیونکہ
انسانی دماغ ابھی نشو و نما پا رہا تھا.وہ ارتقائی منازل کو آہستہ آہستہ طے کر رہا تھا اور ابھی وہ اس
قابل نہیں ہوا تھا کہ شریعت کے باریک احکام یا الہی کلام کی باریک حکمتوں کو سمجھ سکے.مگر
اب تیرے لئے ہم رب الاعلیٰ ہونے کی صورت میں ظاہر ہوئے ہیں.تشبیہ تب دی جاتی ہے
جب کوئی چیز اوپر سے نیچے کی طرف آئے.مگر جب کوئی چیز اونچی چلی جائے تو اس کے لئے
تشبیہات اور استعارات استعمال کرنے کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے.اسی امر کی طرف اشارہ کرتے
ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم تیرے لئے رب الاعلیٰ ہونے کی حیثیت میں ظاہر ہوئے
ہیں.اس لئے تمام تشبیہات کی تشریحات کر دی گئی ہیں.اور بتادیا گیا ہے کہ جب خدا تعالیٰ کو
باپ کہا جاتا تھا تو اُس کے کیا معنے تھے.اور جب کسی نبی کو اُس
کا بیٹا یا اکلوتا بیٹا کہا جاتا تھا تو
اُس کے کیا معنے تھے.توحید کیا ہوتی ہے.شرک کن باتوں سے پیدا ہوتا ہے.شرک کی
کیا کیا قسمیں ہیں.یہ اور اسی قسم کے تمام مسائل کو ہم نے پوری طرح واضح کر کے رکھ دیا
ہے.اس لئے تو جس طرح ان غلطیوں کو دور کر سکتا ہے پہلے لوگ ان غلطیوں کوڈ ور نہیں کر سکتے
تھے.کیونکہ پہلے انبیاء کے لئے ہم رب الاعلیٰ ہونے کی حیثیت میں ظاہر نہیں ہوئے.اس
کے یہ معنے نہیں کہ وہ اُس وقت رب الاعلیٰ نہیں تھا بلکہ اس کے صرف اتنے معنے ہیں کہ ظہورِ
ربوبیت اعلیٰ اس وقت نہیں ہوا تھا.لیکن اس وقت ربوبیت اپنے کمال کو پہنچ گئی ہے.اور
شریعت کو ہر لحاظ سے کامل کر دیا گیا ہے.اس لئے اس کے ہر حکم کی حکمت اور ہر تعلیم کی خوبی
کو واضح کر دیا گیا ہے.اور تیرا فرض ہے کہ تو اُن اعتراضات کو ڈور کرے جو خدا تعالیٰ کی
ذات اور اُس کی صفات اور اُس کی تعلیم وغیرہ کے متعلق کئے جاتے ہیں.اگر اعلیٰ کو اسم کی صفت قرار دیا جائے تو اس کے یہ معنے ہوں گے کہ تیرے رب کا جو نام اعلیٰ
662
Page 671
ہے اُس
کی تسبیح کر.اِس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے ادنی نام بھی ہیں.بلکہ اس کا مطلب یہ
ہے کہ خدا تعالیٰ کی تمام صفات اس وقت اعلیٰ رنگ میں ظاہر ہورہی ہیں.تیرا کام یہ ہے کہ ہر
صفت کا جو اعلیٰ ظہور ہے اُسے پیش کر اور ہر مصیبت پر جو اعتراض پڑتا ہوا سے دُور کرتا کہ
تمام اعتراضات مٹ جائیں اور خدا تعالیٰ کا جلال اپنی پوری شان کے ساتھ دنیا پر ظاہر ہو.اسبح اسم ربك الأغلى کے متعلق یہ امر بھی یاد رکھنا چاہئے کہ رسول کریم صلے اللہ علیہ
وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا طریق یہ تھا کہ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے جب وہ رکوع
میں جاتے تو کہا کرتے اللهُمَّ لَكَ ركعت اور جب سجدہ میں جاتے تو کہتے اللهُمَّ لَكَ
سجدت مگر جب یہ آیت نازل ہوئی کہ سَبْحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلى تو رسول کریم صلے اللہ علیہ
وآلہ وسلم نے فرمایا اِجْعَلُوهَا فِي سُجُودِ كُمْ يتسبيح سجدہ کے وقت کیا کرو.اور جب یہ آیت
نازل ہوئی کہ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ (الحاقه53) تو آپ نے فرمایا اجعَلُوهَا فِي
رُكُوعِكُمْ يتسبیح رکوع کے وقت کیا کرو.چنانچہ یہ جو ہم رکوع میں سُبْحانَ رَبِّي العَظِیم اور
سجدہ میں سُبحان ربی الاعلی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اسی حکم کے نتیجہ میں کہتے ہیں کہ فسيخ باشیم
رَبَّكَ الْعَظِيم اور سَبْحِ اسْمَ رَبِّكَ الأعلى.گویا خدا تعالیٰ نے بتا دیا کہ رکوع میں کس طرح
تسبیح کرنی چاہئے اور سجدہ میں کس طرح تسبیح کرنی چاہئے.ورنہ اس سے پہلے مسلمان رکوع میں
اللهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ اور سجدہ میں اللهُمَّ لَكَ سَجَدُتُ کہا کرتے تھے.الذي خلق فسوى
م خدا تعالیٰ نے پیدا کیا اور اُسے درست اور بے عیب بنایا.اس کے یہ معنے ہیں کہ خدا تعالیٰ
نے انسان کو ایسے رنگ میں پیدا کیا ہے کہ اُس کے اندر تمام ضروری طاقتیں موجود ہیں اور ترقی کے
مادے اُس میں پوری طرح پائے جاتے ہیں گویا وہ سب صفات جو انسانی ترقی کے لئے ضروری
تھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لئے مہیا فرما دی ہیں.اسی بناء پر بائبل میں آتا ہے :.خدا نے انسان کو اپنی صورت میں پیدا کیا.“
( پیدائش 1/27)
663
Page 672
پس سوی کے معنے یہ ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں اعتدال اور ترقی کا ماڈہ پیدا کیا
ہے.ہر قسم کی قابلیتیں اس میں رکھ دی ہیں اور ہر قسم کی ضروریات اس کے لئے مہیا کردی
ہیں اور یہی بے عیب پیدا کرنے کے معنے ہیں.ورنہ بے عیب پیدا کرنے کے یہ معنے تو نہیں
ہو سکتے کہ اس کے اندر خدائی پائی جاتی ہے.اس کے معنی یہی ہیں کہ انسانی پیدائش میں کوئی
چیز ایسی نہیں جس کے متعلق یہ کہا جاسکے کہ وہ لغو اور فضول ہے.مثلاً آنکھ ہے.یہ بالکل بیکار
ہوتی اگر اُس کے مقابل میں سورج کی روشنی پیدا نہ کی جاتی.مگر اللہ تعالیٰ کا احسان دیکھو کہ اُس
نے ایک طرف آنکھ پیدا کی تو دوسری طرف سورج کی روشنی پیدا کر دی تا کہ آنکھ کام کر سکے.اسی طرح تمام جسم انسانی کو دیکھ لو ہر چیز کسی نہ کسی غرض کے لئے پیدا کی گئی ہے.اور اُس کا
ضرور کوئی نہ کوئی فائدہ ہے.صرف دو چیزیں انسانی جسم میں ایسی ہیں جن کے متعلق ڈاکٹروں کا
یہ خیال تھا کہ ان کی کوئی غرض نہیں یہ یونہی پیدا کر دی گئی ہیں.ایک تو کان کی لو کے متعلق
خیال کیا جاتا تھا کہ یہ کسی خاص غرض کے لئے نہیں ہے.دوسرے معاء اعور یعنی اپنڈکس کے
متعلق یہ خیال کیا جاتا تھا کہ جسم انسان میں اس کا کوئی خاص کام نہیں.بعض اور چیزیں بھی
تھیں جن کے متعلق پہلے زمانہ میں یہ خیال کیا جاتا تھا کہ وہ بے فائدہ پیدا کی گئی ہیں لیکن آہستہ
آہستہ ان کی ضرورت کو اطباء نے ظاہر کر دیا.صرف یہ دو چیز میں رہ گئی تھیں مگر آج سے چالیس
پچاس سال پہلے معاء اعور کی ضرورت کو بھی ڈاکٹروں نے محسوس کر لیا.چنانچہ فرانس کے ایک
ڈاکٹر نے یہ معلوم کرنے کے لئے کہ آیا معاء اعور کا کوئی فائدہ ہے یا نہیں بارہ بندر لئے اور اُن
میں سے چھ کے اپنڈکس اپریشن کے ذریعہ کاٹ دیئے اور چھ کے رہنے دیئے.اس کے بعد
اُس نے تمام بندروں کی یکساں پرورش شروع کر دی اور یہ غور کرنا شروع کیا کہ آیا دونوں میں
کسی قسم کا کوئی فرق پیدا ہوتا ہے یا نہیں.کچھ عرصہ کے بعد اُس نے دیکھا کہ جن بندروں کے
اپنڈکس کاٹ دیئے گئے تھے اُن کی قوت مقاومت کم ہو گئی ہے.وہ بیماریوں کا جلد شکار ہو
جاتے ہیں اور غذا اُن کے جسم کو لگتی نہیں.لیکن دوسرے بندر جن کا اپریشن نہیں کیا گیا تھا وہ
664
Page 673
اسی طرح مضبوط رہے ہیں جس طرح پہلے تھے.اس سے ثابت ہو گیا کہ اپنڈکس جس کے
متعلق خیال کیا جاتا تھا کہ شائد اس کا کوئی فائدہ نہیں، یہ ایک زائد آنت ہے جو جسم انسان
میں پیدا ہو گئی ہے، اس کا بھی انسانی جسم کی صحت کے ساتھ گہرا تعلق ہے.اور جن لوگوں کی یہ
آنت کاٹ دی جائے اُن کی قوتِ مقاومت کم ہو جاتی ہے.مگر اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہئے کہ
قوت مقاومت دوسروں کے مقابلہ میں کم ہو جاتی ہے بلکہ قومت مقاومت کے کم ہونے کے یہ
معنے ہیں کہ جتنی طاقت اس آنت کی موجودگی میں اُس کے اندر پائی جاتی ہوا پریشن کے بعد اتنی
طاقت اس کے اندر نہیں رہتی.ورنہ ہوسکتا ہے کہ ایک شخص کا اپریشن نہ ہوا ہو اور کسی اور وجہ
سے اُس کے اندر مقابلہ کی طاقت کم ہو.اس صورت میں اُس کا اور اپریشن والے شخص کا مقابلہ
نہیں ہو گا بلکہ دیکھا یہ جائے گا کہ اس شخص کے اندر پہلے کتنی طاقت مقابلہ تھی اور اب کتنی
ا
طاقت مقابلہ رہ گئی ہے.اِس موازنہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اپریشن سے پہلے انسان کے اندر
جتنی تاب مقاومت ہوتی ہے اپریشن کے بعد اتنی طاقت اُس میں نہیں رہتی بلکہ ضرور اُس میں
کمی آجاتی ہے.فرانس کے اس ڈاکٹر نے جو تجربہ کیا اُس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اپنڈکس کا
انسان کی قوتِ مقاومت اور اُس کی صحت کی بحالی کے ساتھ گہرا تعلق ہے.ممکن ہے آئندہ چل
کر اس سے بھی زیادہ واضح طور پر اس کے فوائد ثابت ہو جائیں لیکن بہر حال اس وقت تک کی
تحقیق یہی ثابت کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو بے فائدہ پیدا نہیں کیا.دوسری چیز
جسے بیکار سمجھا جاتا تھا کان کی لو ہے.مگر اب معلوم ہوا ہے کہ یہ بھی بیکار نہیں بلکہ آواز کے سُننے
میں یہ ایک لطیف قسم کا اثر رکھتی ہے جس طرح بچے پتنگ کے ساتھ ایک چھوٹی سی دھجی یا پتلا سا
کاغذ باندھ دیتے ہیں جو بظاہر زائد چیز نظر آتی ہے مگر پتنگ کے اُڑانے میں وہ بہت کام آتی
ہے.اسی طرح کان کی کو علاوہ اس کے کہ کان کو خوبصورت بنادیتی ہے آواز کے ساتھ بھی گہرا
تعلق رکھتی ہے.بعض حصے جسم انسانی میں ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی کے لئے پیدا
کئے ہیں.انہی میں سے ایک کان کی کو بھی ہے.اگر کسی کے کان کی کو کاٹ دی جائے تو بالکل
665
Page 674
بھیجا سا نظر آنے لگ جائے گا.اور اُس کی ساری خوبصورتی ماری جائے گی.لیکن علاوہ خوبصورتی
کے اس کو کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ چونکہ اس کے اندر لچک پائی جاتی ہے اس وجہ
سے آواز اُس کے ذریعہ سے ایک لہر پیدا کر دیتی ہے جس کی وجہ سے آواز زیادہ محمدگی سے سنی
جاسکتی ہے.یہ ایک موٹا فائندہ کان کی لو کا ہے.اور بھی کئی فوائد ہوں گے جو اپنے اپنے وقت
ظاہر ہوتے رہیں گے.پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اُس نے انسان کو پیدا کیا اور پھر اُسے بے
عیب بنایا ہے.کوئی چیز ایسی نہیں جس کی کوئی نہ کوئی غرض نہ ہو.ہر چیز اللہ تعالیٰ نے حکمت
اور انسانی فائدہ کو مدنظر رکھتے ہوئے پیدا کی ہے.پھر خَلَقَ فَسَوی کے یہ بھی معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو معتدل القویٰ بنایا ہے
اور اُس کی قوتوں میں اُس نے ہر لحاظ سے اعتدال پیدا کیا ہے.خَلَقَ فَسَوی کے ایک یہ بھی معنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور پھر
جب جب اُس میں خرابی پیدا ہوئی اللہ تعالیٰ نے اُس کی درستی کے سامان کئے اور اس کی کجی کو
دور کیا.تشویہ کے ایک معنے...عیب پیدا ہونے پر اُس عیب کو دور کرنے کے ہوتے
ہیں.پس خَلَقَ فَسَوی کے ایک معنے یہ بھی ہیں کہ اُس نے انسان کو پیدا کیا اور پھر جب کبھی
اُس میں خرابی پیدا ہوئی اللہ تعالیٰ نے اُس کو ڈور کیا.جو خدا اپنے بندوں کا اس قدر خیال رکھتا
ہے اور ہر خرابی پر اس کو ڈور کرنے کے سامان مہیا کرتا ہے اس کی طرف یہ عیب کبھی منسوب
نہیں کیا جا سکتا کہ خرابی تو پیدا ہومگر وہ اُس کوڈ ورکرنے کے سامان مہیا نہ کرے.وَالَّذِي قَدَّدَ فَهَدَى
لا قدرة على الشني کے معنے ہوتے ہیں جَعَلَهُ قَادِرًا اُس کو قادر بنا دیا.اور قدر فُلان
کے معنے ہوتے ہیں روی وَفَكَّرَ في تَسْوِيَةِ أَمْرِه اُس نے کسی معاملہ میں غور کیا اور سوچا کہ
اُسے کس طرح سر انجام دے.قَدَّدَ الشَّيئ بِالشَّني کے معنے ہوتے قَاسَهُ بِهِ وَجَعَلَهُ عَلَى
مقدارہ اُس نے ایک چیز کو دوسری پر قیاس کیا اور اُس کے مطابق اسے بنایا.یہ بھی کہ
666
Page 675
قَدَّرَهُ عَلَى الشَّيي يعني قَدَّرَ الْإِنْسَانَ عَلَى الْهُدَى اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہدایت پر قادر بنایا
ہے.یعنی اُسے اس قابل بنایا ہے کہ وہ ہدایت پائے اور ترقی کرے.دوسرے معنوں کے لحاظ سے وَالَّذِي قَدَّرَ فَھدی کا یہ مفہوم ہو گا کہ جس نے انسان کی
حالت کا ہمیشہ اندازہ لگایا.کیونکہ قدر فلان کے معنے ہوتے ہیں رَوی وَفَكَّرَ فِي تَسْوِيَةِ أَمْرِه
پس قدر فَهَدی کے معنے یہ ہوئے کہ جب کبھی خرابی پیدا ہوئی اللہ تعالیٰ نے اُس کوڈ ورکر نے
کی تجویز کی.اور اُس کا خرابی کو دور کرنے کی تجویز کرنا سرسری نہ تھا بلکہ ہمیشہ اُس نے اندازہ
لگایا کہ خرابی کس قسم کی ہے، کتنی بیماری ہے اور کس قدر علاج سے وُہ دُور ہوسکتی ہے.در حقیقت علاج میں اسی وقت کامیابی ہوتی ہے جب مرض کے مطابق علاج کیا جائے.یہ کبھی
نہیں ہوگا کہ ایک شخص کو معمولی ملیر یا بخار ہوتو ڈاکٹر اسے روزانہ ساٹھ گرین کو نین کھلانا شروع
کردے لیکن ایک دوسرا شخص جسے شدید ملیر یا ہوا سے ڈاکٹر بعض دفعہ اتنی کونین کھلاتا ہے کہ
اُس کے کان بہرے ہو جاتے ہیں.اب اگر کوئی شخص کہے کہ فلاں شخص کو کونین زیادہ کیوں
دی گئی اور فلاں کو کم کیوں تو یہ اُس کی نادانی ہوگی.کیونکہ علاج مرض کے مطابق ہوتا ہے.اسی
طرح اللہ تعالیٰ بھی ہمیشہ خرابی کے مطابق اصلاح کے سامان پیدا فرماتا ہے.اور قدر فَهَدی
میں اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مرض کے متعلق پہلے اندازہ لگایا کہ کیا مرض ہے.وہ شدید ہے یا خفیف.کتنے علاج سے وہ اچھی ہو سکتی ہے.اور پھر اُس اندازہ کے مطابق
علاج نازل کیا.اقر کے ایک یہ معنی بھی تھے کہ قَاسَهُ بِهِ وَجَعَلَهُ عَلَی مِقْدَارِہ اُس نے ایک چیز کو
دوسری چیز پر قیاس کیا اور اُس کے مطابق اُسے بنایا.اس لحاظ سے آیت کے معنے یہ ہوں گے
کہ انسان کی مرض اور اُس کے علاج کا موازنہ کر کے اللہ تعالیٰ نے اُس کی اصلاح اور درستی
کے سامان مہیا کئے.پہلے معنے تو یہ تھے کہ جس قسم کی مرض تھی اسی قسم کا علاج نازل کیا اور
دوسرے معنے یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مرض کا اندازہ کیا اور پھر جتنی مرض تھی اتنا علاج بھیج دیا.ا خَلَقَ فَسَوی کے دو معنے کئے گئے تھے.ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو
667
Page 676
معتدل القویٰ اور ترقی کرنے والا بنایا.دوسرے یہ کہ جب بھی اُس میں کوئی خرابی پیدا ہوئی اللہ
تعالیٰ نے اُس کو دُور کیا.اِن دونوں معنوں کے لحاظ سے قدَّدَ فَهَدی کے بھی دو معنے ہوں
گے.پہلے معنوں کے مقابلہ پر یہ کہ چونکہ انسان میں ترقی کی استعداد رکھی گئی تھی اور اسے کامل
القویٰ بنا دیا گیا تھا.محمد اتعالیٰ نے اُس کی طاقتوں کا اندازہ کر کے اس کے متواتر ترقی کرتے
چلے جانے کے ذرائع مہیا کئے.دوسرے معنے الَّذِی خَلَقَ فَسَوی کے یہ تھے کہ جب کبھی اس میں خرابی پیدا ہوئی اور وہ
حج ہوا اللہ تعالیٰ نے اس کی ضرورت کے مطابق اُس کی اصلاح کے سامان کئے اور اس کی کجی
کوڈ ور کر دیا.ان معنوں کے لحاظ سے وَالَّذِي قَدر فَھدی کے یہ معنے ہوں گے کہ جب بھی وہ
کج ہوا اُس کی ضرورت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ہدایت بھیجوا دی.اور اس طرح اُس کی
اصلاح کی.اگر ضرورت کے مطابق ہدایت نہ ہوتی یا کم ہوتی تو وہ گمراہ ہو جاتا اور اگر ضرورت
سے بڑھ جاتی تب بھی اُس کی قوتیں ٹوٹ جاتیں اور وہ حیران رہ جاتا.پس اصلاح کا اُس نے
صحیح طریق اختیار کیا اور اس قدر جو ضروری تھا نازل کیا.گویا جیسی جیسی مرض تھی اور جتنی جتنی کجی
پائی جاتی تھی اُس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے علاج نازل کیا.غرض پہلی آیت کے جو دو معنے کئے گئے تھے اُن کے لحاظ سے اس آیت کے بھی دو معنے
ہیں.ایک یہ کہ اُس نے انسان کی استعداد کمال کو ضائع نہیں ہونے دیا بلکہ ہمیشہ اس کے
بڑھنے کے ذرائع مہیا کئے.دوسرے یہ کہ مرض پیدا ہونے پر اُس مرض کے مطابق علاج
نازل کیا.ایک معنوں کے لحاظ سے ترقی کی طرف اشارہ ہے اور دوسرے معنوں کے لحاظ سے
ازالہ مرض کی طرف اشارہ ہے..حمد اس آیت کے ایک اور معنے بھی ہیں اور وہ یہ کہ بیشک اللہ تعالیٰ نے انسان کو معتدل
القویٰ اور نقائص سے پاک بنایا ہے.مگر اس کے ساتھ ہی اُس نے انسان کے لئے کئی قسم کی
حد بندیاں بھی قائم کر دی ہیں.یہ نہیں کہ وہ اُن قوتوں کو بے تحاشا استعمال کرنا شروع کر دے.668
Page 677
اسی مضمون کے مطابق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر انسان کے ارد گرد ہم نے ایک
حد بندی قائم کر دی ہے جس میں سے وہ باہر نہیں نکل سکتا.یہی وہ حد بندی ہے جسے ماحول کہتے
ہیں.گویا قدر فهدى سے اللہ تعالیٰ نے اِس طرف اشارہ کیا ہے کہ انسان اپنے ماحول کے
مطابق چلتا ہے اُس نے صرف قوی ہی پیدا نہیں کئے بلکہ ان قویٰ کے ظہور کے لئے ایک
ماحول بھی پیدا کیا ہے.اس ماحول کو دیکھو اس کے مطابق ہی قوی ظاہر ہو سکتے ہیں.پس اللہ
تعالیٰ نے جب بھی ہدایت نازل کی ہے ماحول کو مد نظر رکھا ہے.یہ ماحول مادی بھی ہوتا ہے
اور دینی بھی.مادی ماحول تو حیوان اور انسان سب کے لئے ہے مگر دینی ماحول یعنی شریعت
صرف انسان کے لئے ہے اور پھر شریعت بھی مادی ماحول کے مطابق ہوتی ہے.یہی مضمون
اللہ تعالیٰ نے قدَّدَ فَهَدَی میں بیان کیا ہے اور بتایا ہے کہ تم اس حقیقت کو
ہمیشہ یاد رکھو کہ تعلیم ہمیشہ ماحول کے مطابق اُترے گی.اگر ماحول کے مطابق اللہ تعالیٰ کی
طرف سے تعلیم نازل نہ ہو تو خواہ وہ کتنی ہی اعلیٰ ہو انسان کو بلاک کرنے والی ہوگی اُسے ترقی کی
منازل کی طرف لے جانے والی نہیں ہوگی.وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرغى
مرغی اس گھاس پھونس کو کہتے ہیں جس کو جانور کھاتا ہے.اور مرغی چراگاہ کو بھی
کہتے ہیں ( اقرب) اِس آیت میں مرغی سے مراد گھاس پھونس ہے.چراگاہ مراد نہیں.فَجَعَلَهُ عُمَّاءَ أَحْوَى.ا تقاء.یہ لفظ خُفاء اور عُقاء دونوں طرح بولا جاتا ہے اور اس کے معنے رڈی چیز کے
ہوتے ہیں.ہر قسم کی چیز جورڈی ہو جائے اُس کے متعلق کہتے ہیں وہ خُفاء ہوگئی اور محتاج
کے معنی جھاگ کے بھی ہوتے ہیں اور غقا کے معنے بلاک ہونے والی چیز کے بھی ہوتے
ہیں.اور غقا درخت کے ان پتوں کو بھی کہتے ہیں جو گر کرسٹر جاتے ہیں.اور جب بارش کا
پانی یا سیلاب آتا ہے تو باغوں میدانوں اور گلیوں میں سے اُن سڑے ہوئے پتوں کو پانی اُٹھا
669
Page 678
لیتا ہے اُس وقت جھاگ میں مل کر اُن گلے سڑے پتوں کے جو بار یک باریک ذرات نکلتے
ہیں اُن کو بھی عُشَاءِ باغقا کہتے ہیں.(اقرب)
آخوى به لفظ حوتی سے نکلا ہے.حوی الشیخ کے معنے ہوتے ہیں گان به حوة اس
میں کوہ پایا جاتا ہے (اقرب) اور حوق کے معنے ہوتے ہیں ایسی سیاہی جو سبزی کی طرف مائل
ہو.یا ایسی سُرخی جو سیاہی کی طرف مائل ہو.(اقرب) پس آخوی کے معنے ہوئے ایسی سیاہ
رنگ والی چیز جس میں کچھ سبزی کی جھلک پائی جاتی ہو.یا ایسی سُرخ رنگ والی چیز جس میں
کچھ سیاہی کی جھلک پائی جاتی ہو.اگر صرف تقاء کا لفظ استعمال کیا جاتا تو اس کے معنے یہ ہوتے کہ وہ بیکار اور گندی چیز ہو
جاتی.مگر فقاء کے ساتھ خدا تعالیٰ نے آخوی کا لفظ بھی بڑھا دیا یہ بتانے کے لئے کہ وہ اتنی
گندی اور خراب ہو جاتی ہے کہ اپنا رنگ بھی چھوڑ دیتی ہے.سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسى
امام راغب کہتے ہیں نسیان کے ایک معنے یہ ہیں کہ جس چیز کا خیال رکھنا انسان کے
سپر دتھا اُس نے اُس کا خیال ترک کر دیا.اِمَّا لِضُعْفِ قلبہ.یا تو حافظہ کی خرابی کی وجہ سے
یعنی وہ بھول گیا.اَوْ عَنْ قَصْدٍ حَتَّى يَنْحَذِفَ عَنِ الْقَلْبِ ذِكْرُۂ.اور یا جان بوجھ کر وہ اس کا
خیال اپنے ذہن میں نہیں آنے دیتا.یعنی وہ چیز اسے بھولی تو نہیں مگر اس پر عمل کرنا اُس نے
چھوڑ رکھا ہے اور اُس کے ساتھ اس کا تعلق کم ہو گیا ہے.گویا لغتا ترک عمل کے لئے بھی نسیان کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے.پس فلا تنسی کے
دو معنے ہوئے ایک یہ کہ تم اُسے بھولو گے نہیں اور دوسرے یہ کہ تم اسے چھوڑو گے نہیں.یعنی
اُس پر عمل کرنا ترک نہیں کرو گے.آج دنیا کے پردہ پر کوئی ایک کتاب بھی ایسی نہیں جس کے متعلق یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہو کہ
جس شکل وصورت میں اُس کتاب کو مذہب کے بانی نے پیش کیا تھا اسی شکل وصورت میں وہ
670
Page 679
اب دنیا کے سامنے موجود ہے.اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ خدا تعالیٰ نے ان کتابوں کے
متعلق یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ وہ مٹ جائیں.کیونکہ خدا تعالیٰ چاہتا تھا اُن کی جگہ اور کتاب نازل
کرے.ورنہ اگر خدا تعالیٰ کا یہ منشاء تھا کہ تو رات دنیا میں قائم رہے تو جس خدا تعالیٰ نے موسلی
پر تورات نازل کی تھی کیا وہ اس بات پر قادر نہیں تھا کہ اس کے مٹ جانے کی صورت میں
دوبارہ ایک نبی موسی" جیسا کھڑا کر دیتا.اور کہتا کہ چونکہ تورات مٹ گئی ہے اس لئے اب میں
تجھ پر اصل تو رات نازل کرتا ہوں اسے دنیا میں پھیلا.یا کیا حد اتعالیٰ یہ بھی نہیں کر سکتا تھا کہ
جولوگ تو رات کو مٹانے لگے تھے اُن کو خود اپنے عذاب سے بلاک کر دیتا.اس طرح اگر
ژند اوستا قائم رہنے والی چیزیں تھیں اور خدا تعالیٰ کا منشاء یہ تھا کہ وہ دُنیا میں محفوظ رہیں اور لوگ
اُن پر عمل کریں تو کیا سکندر کو خُدا تعالیٰ اپنے عذاب سے
کچل نہیں سکتا تھا.اگر خد اتعالیٰ کا یہ
منشاء تھا کہ ویدوں پر ہی عمل کیا جائے تو کیا خدا اُن پنڈتوں اور ودوانوں کو مار نہیں سکتا تھا
جنہوں نے وید بدلنے کی کوشش کی.اگر خدا تعالیٰ کا منشاء یہ تھا کہ تو رات اپنی اصل صورت
میں قائم رہے تو کیا خدا تعالی بخت نصر کو شکست نہیں دے سکتا تھا.اگر خدا تعالیٰ کا منشاء یہ تھا
کہ دنیا کا انجیل پر ہی عمل رہے تو کیا اللہ تعالیٰ ان خرابیوں کو جو عیسائیوں نے انجیل میں پیدا کر
دیں دُور نہیں کر سکتا تھا.یقیناً خدا تعالیٰ ایسا کر سکتا تھا.مگر خدا تعالیٰ نے ان تغیرات کو ہونے
دیا.کیونکہ خدا تعالیٰ کا یہ منشاء تھا کہ یہ کتابیں دُنیا میں محفوظ نہ رہیں.دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جن چیزوں کو خدا تعالیٰ بچانے کا ارادہ رکھتا ہے دُنیا
لاکھ کوشش کرے وہ اُن چیزوں کو بگاڑ نہیں سکتی.اللہ تعالیٰ کی سنت سے یہ ثابت ہے کہ وہ الہامی کتب کو اُس وقت تک جب تک وہ دُنیا
کے لئے مفید اور نفع رساں رہتی ہیں ہر قسم کے تصریف اور تحریف والحاق سے محفوظ رکھتا ہے.مگر
جب اُن کا کام ختم ہوجاتا ہے تو دُنیا اُن میں بگاڑ پیدا کرنا شروع کر دیتی ہے.اسی طرح پیدائش
عالم میں جو چیزیں عارضی فوائد کی حامل ہوں وہ ایک عرصہ کے بعد سٹر گل جاتی ہیں مگر جو چیزیں
671
Page 680
لمبے فوائد کی حامل ہوں وہ چلتی چلی جاتی ہیں.اسی دلیل کا ذکر اللہ تعالی اس آیت میں کرتا ہے اور
فرماتا ہے سَنُقْرِئُكَ فَلا تنسى ہم تجھے وہ تعلیم دیں گے جسے تو بھولے گا نہیں.یہاں تو سے
مراد صرف رسول کریم صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں بلکہ ساری امت محمدیہ مراد ہے.اور یہ قرآن کریم
کا طریق بیان ہے کہ کہیں صرف نبی کو مخاطب کیا جاتا ہے مگر مرادساری جماعت ہوتی ہے.پس
تو بھولے گا نہیں“ سے یہ مراد نہیں کہ صرف رسول کریم صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں بھولیں گے
بلکہ مراد یہ ہے کہ اُمت محمدیہ اس کو نہ بھولے گی اور اس کے الفاظ محفوظ رکھے جائیں گے.چنانچہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِكرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (الحجر (10) ہم
نے ہی قرآن کریم نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کا وعدہ کرتے ہیں.اسلام کے اشد ترین معاند بھی آج گھلے بندوں
یہ تسلیم کرتے ہیں کہ قرآن کریم اسی شکل
وصورت میں محفوظ ہے جس شکل وصورت میں رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم نے اُس کو پیش
فرمایا.نولڈ کے سپر نگر اور ولیم میور سب نے اپنی کتابوں میں تسلیم کیا ہے کہ قطعی اور یقینی طور پر
ہم سوائے قرآن کریم کے اور کسی کتاب کے متعلق یہ نہیں کہہ سکتے کہ جس شکل میں بانی سلسلہ
نے وہ کتاب پیش کی تھی اسی شکل میں وہ دنیا کے سامنے موجود ہے.صرف قرآن کریم ہی ایک
ایسی کتاب ہے جس کے متعلق حتمی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ جس شکل میں محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ کتاب دی تھی اسی شکل میں اب بھی محفوظ ہے.الغرض یورپین مصنفین نے یہ بھی تسلیم کیا ہے کہ جہاں تک قرآن کی ظاہری حفاظت کا
سوال ہے اس میں کسی قسم کا شبہ نہیں کیا جا سکتا.بلکہ لفظا لفظا اور حرفا حرفا یہ وہی کتاب ہے جو
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو پڑھ کر سُنائی.لید غور کرو اور سوچو کہ یہ کتنی عظیم الشان پیشگوئی ہے جو ان چند الفاظ میں کی گئی کہ سَنُقْرِئُكَ
فلا تنسی.اور پھر یہ پیشگوئی اس زمانہ میں کی گئی ہے جب رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم پر صرف
چھ لوگ ایمان لانے والے پائے جاتے تھے ساری دنیا آپ کی مخالف تھی.اور وہ آپ کے نام کو
672
Page 681
صفحہ ہستی سے معدوم کرنے کے لئے محلی ہوئی تھی.یہ نہیں کہ لاکھوں اور کروڑوں لوگ آپ کے
ساتھ ہوں اور آپ ایک جتھا کو اپنے ارد گرد دیکھ کر کہنے لگ گئے ہوں کہ اب اس کتاب کو کوئی مٹا
نہیں سکتا بلکہ آپ یہ پیشگوئی ایسی حالت میں کرتے ہیں جب آپ دنیا کے ہر تیر کا نشانہ بنے
ہوئے تھے اور آپ پر ایمان لانے والے انگلیوں پر گنے جاسکتے تھے.ایسی نازک اور کمزور حالت
میں آپ فرماتے ہیں یہ قرآن دُنیا میں قائم رہے گا اور کوئی شخص اس کو مٹانے کی قدرت نہیں
رکھے گا.لاکھوں اور کروڑوں ماننے والوں کے ہوتے ہوئے وید بدل گئے.لاکھوں اور کروڑوں
ماننے والوں کے ہوتے ہوئے تو رات بدل گئی.لاکھوں اور کروڑوں ماننے والوں کے ہوتے
ہوئے انجیل بدل گئی.لاکھوں اور کروڑوں ماننے والوں کے ہوتے ہوئے زرتشت کی کتابیں بدل
گئیں.لیکن ایک انسان جس کے ساتھ صرف اتنی ، توے آدمی ہیں.وہ ایک ایسے ملک میں جہاں
حفاظت کا کوئی سامان نہ تھا.جہاں
کسی قسم کی لائبریریاں نہ تھیں.جہاں
کسی قسم کی تعلیم کا رواج نہ
تھا.اعلان کرتا ہے کہ میری یہ کتاب ہمیشہ محفوظ رہے گی.قیامت تک قائم رہے گی.اور دنیا اس
کے ایک شوشہ کو بھی بدلنے کی طاقت نہیں رکھے گی.اگر مکہ کے لوگ پڑھے لکھے ہوتے تب بھی
خیال کیا جا سکتا تھا کہ شائد مکہ کے لوگوں کی تعلیمی قابلیت کو دیکھ کر ایسا اعلان کیا گیا ہے.مگر اللہ
تعالیٰ کی قدرت دیکھو کہ اسلام ان لوگوں میں آیا جو لکھنا بھی نہیں جانتے تھے.ابتدائی مگی صحابہ
میں سے صرف تین چار ایسے تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے.زیادہ سے زیادہ سات افراد سمجھ لو.اور
گل جماعت جو آپ کے ارد گرد تھی وہ اسی نوے افراد سے زیادہ نہیں تھی.ایسی حالت میں یہ کتنی
زبر دست اور عظیم الشان پیشگوئی ہے کہ ہم تجھے قرآن پڑھائیں گے جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تو قرآن کو
بھولے گا نہیں.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے دوسروں کو خاص طور پر نہیں پڑھایا مگر تیرے لئے
چونکہ ہماری ربوبیت اعلیٰ ظاہر ہوئی ہے اس لئے ہم تجھے ایسے اعلی درس دیں گے جو تجھے کبھی نہیں
بھولے گا.یعنی وہ کلام جو تجھ پر نازل ہوگا وہ ہمیشہ دنیا میں قائم رہے گا.673
Page 682
إِلَّا مَا شَاءَ اللهُ
اب ایک سوال رہ جاتا ہے کہ اگر اس کتاب نے ہمیشہ رہنا تو پھر بتائیے کسی موعود کی
کیا ضرورت ہے؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے اگلے حصہ میں دیا ہے.اس آیت کے متعلق بوجہ ان معنوں کے نہ کرنے کے جو میں نے اوپر بیان کیا ہے
مفسرین کو سخت دقت پیش آئی ہے اور وہ حیران ہوئے ہیں کہ الَّا مَا شَاءَ اللہ کے اس جگہ کیا
معنے ہوئے؟ کیا قرآن کا کچھ حصہ اُڑ جائے گا کہ خدا تعالیٰ نے فَلا تنسی کے ساتھ
إِلَّا مَا شَاء اللہ بھی کہہ دیا.اس وقت کو حل کرنے کے لئے بعض نے تو کہہ دیا ہے کہ الا
مَا شَاءَ الله سے منسوخ آیات مراد ہیں.مگر یہ درست نہیں.اس لئے کہ جن آیات کو منسوخ
قرار دیا جاتا ہے وہ یا تو قرآن کریم میں آج تک لکھی ہوئی موجود ہیں یا اس عقیدہ کے رکھنے
والوں کے قول کے مطابق اگر وہ منسوخ التلاوۃ بھی ہیں تو آج تک تفسیروں میں لکھی ہوئی ہیں.مگر خدا تعالیٰ اس جگہ فرماتا ہے کہ وہ بھول جائیں گی.جب وہ سب کی سب قرآن کریم یا
تفسیروں میں موجود ہیں تو بھول کس طرح جائیں گی.یہ امر یا درکھنا چاہئے کہ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ قرآن کریم میں کوئی آیت منسوخ بھی
ہے.ہم قرآن کریم کے ایک ایک لفظ کو قابل عمل سمجھتے ہیں.لیکن وہ لوگ جو قرآن کریم میں
ناسخ منسوخ کے قائل ہیں میں اُن کا ذکر کر رہا ہوں کہ اُن کا یہ استدلال درست نہیں.اس لئے
که فلا تنسی کے ساتھ الَّا مَا شَاء اللہ کا ذکر کیا گیا ہے اور نسخ اول تو بھولنے کو نہیں کہتے.پھر جب کہ وہ سب آیات جن کو منسوخ قرار دیا جاتا ہے یا تو قرآن کریم میں یا تفاسیر میں موجود
اور لکھی ہوئی ہیں تو وہ بھول کس طرح گئیں.واقعہ بھی یہ ہے کہ وہ سب اسی طرح موجود ہیں اور
کسی کو بھی بھولی نہیں.پس یہ معنے تو درست نہیں ہو سکتے.اصل بات یہ ہے کہ نسیان دو قسم کا ہوتا ہے.کبھی لفظا نسیان ہوتا ہے اور کبھی معنا نسیان ہوتا
ہے.جب ہم کسی چیز کو بھول جانے کا ذکر کرتے ہیں تو اس کے دو معنے ہوتے ہیں.اوّل یہ کہ
674
Page 683
اُس کا وجود بھول گیا یعنی وہ الفاظ جو پہلے یاد تھے حافظہ میں سے نکل گئے ہیں یا شکل جو پہلے ذہن میں
مستحصہ تھی وہ اب جاتی رہی ہے.لیکن کبھی اس کے معنے حقیقت کو بھول جانے کے ہوتے ہیں.حمد اس آیت میں الا سے اس دوسری قسم کے نسیان کی طرف ہی اشارہ ہے اور اللہ تعالیٰ
فرماتا ہے کہ سَنُقْرِئُكَ فَلا تنسی ہم مجھ کو قرآن کریم پڑھائیں گے ( اور تجھ سے مراد جیسا کہ
میں بتا چکا ہوں رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ امت محمدیہ مراد ہے ) اور تو اس قرآن کو
نہیں بھولے گا.یعنی تیری اُمت اس قرآن کو نہیں بھولے گی.إِلَّا مَا شَاء الله مگر وہ حصّہ جو
خدا چاہے گا بھول جائے گا.یعنی ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مسلمان لفظا تو قرآن کریم کو یاد
رکھیں گے مگر معنا اُس کو بھول جائیں گے.الفاظ کو تو قائم رکھیں گے مگر آدم کی طرح الفاظ کی
رُوح کو بھول جائیں گے.جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِي عَلَى
النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا اسْمُهُ وَلَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُهُ (مشكوة
کتاب العلم صفحه (38) یعنی ایک زمانہ ایسا آئے گا جب قرآن کے صرف الفاظ باقی رہ
جائیں گے.ایمان اور اسلام کی رُوح اُڑ جائے گی.اسی کا اِلَّا مَا شَاءَ اللہ میں استثناء کیا گیا
ہے.اور بتایا گیا ہے کہ تم اس قرآن کو نہیں بھولو گے مگر ایک قسم کا نسیان ہو سکے گا.یہ مطلب
نہیں کہ سورۃ اعراف نہیں مٹے گی اور سورۃ مائدہ مٹ جائے گی.یا سورۃ کوثر نہیں مٹے گی اور
سورۃ الناس مٹ جائے گی.بلکہ مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ تو باقی رہیں گے مگر معنی
اُڑ جائیں گے.پس الا اس جگہ قرآن کریم کے الفاظ کے ٹکڑوں کے استثناء کے طور پر استعمال
نہیں ہوا بلکہ دو قسم کی حفاظتوں میں سے ایک قسم کی حفاظت کی نسبت استعمال ہوا ہے.اور اس
میں قول فصل کے متعلق اس اعتراض کا جواب دیا گیا ہے کہ اگر یہ قول فصل ہے تو پھر کسی اور
مامور کی کیا ضرورت ہے.سو بتایا کہ قرآن کریم کے ظاہر کی حفاظت غیر فاصل کا وعدہ ہے.اس کی معنوی غیر فاصل حفاظت کا وعدہ نہیں.وہ مستقل تو ہو گی مگر غیر فاصل نہیں.جب اللہ
تعالیٰ لوگوں کو نااہل پائے گا مغز.قرآن اُڑ جائے گا.جسے واپس لانے کے لئے پھر ایک
675
Page 684
مامور کی ضرورت ہوگی.إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يخفى
إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخفی اس آیت میں اللہ تعالیٰ وجہ بیان فرماتا ہے کہ کیوں ایک
زمانہ میں مغز قرآن دُنیا سے اُٹھ جائے گا اور صرف الفاظ لوگوں کے پاس باقی رہ جائیں گے.فرماتا ہے خدا لوگوں کی قلبی اور اُن کی ظاہری حالت کو خوب جانتا ہے.جب تک مسلمانوں کا ظاہر
بھی درست رہے گا اور ان کا باطن بھی درست رہے گا قرآن ظاہر میں بھی محفوظ رہے گا اور باطن میں
بھی محفوظ رہے گا.جب مسلمان صرف ظاہر میں مسلمان کہلائیں گے اُن کا باطن خراب ہو جائے
گا.قرآن کا بھی صرف ظاہر ٹھیک رہے گا اُس کا باطن یعنی مغز ان سے اڑ جائے گا.خدا ظاہر کو بھی
جانتا ہے اور باطن کو بھی جانتا ہے.جب مسلمانوں کے دل میں ایمان نہیں رہے گا تو اللہ تعالیٰ
قرآن کریم کے معنے اُن پر کیوں کھولے گا.قرآن کریم تو ایک نور ہے جو صرف نورانی لوگوں پر گھل
سکتا ہے.بد عمل اور بے ایمان لوگ اس کے معارف سے آگاہ نہیں ہو سکتے.پس الا ماشاء الله
میں مسلمانوں کی آخری زمانہ کی حالت کا نقشہ کھینچا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں پر ایک
زمانہ ایسا آنے والا ہے جب وہ الفاظ کو تو یا درکھیں گے مگر عمل کرنا بھول جائیں گے.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے چونکہ ظاہر میں یہ شریعت ہمیشہ محفوظ رہے گی اس لئے ظاہر میں
کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں ہو گی.لیکن باطن میں چونکہ نقص پیدا ہوتا رہے گا اس لئے
ضروری ہے کہ افہام و تفہیم کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے انبیاء اور مامور مبعوث
ہوتے رہیں جو قرآن کریم کی معنوی حفاظت کا فرض سر انجام دیں.اور جس چیز کو لوگ بھول
چکے ہوں اُس کو دوبارہ الہی تائید سے تازہ کر دیں.ولييرُ الكَلِلْيُسْرى
اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ مضمون بیان فرماتا ہے کہ تیرے دین کی حفاظت اور اُس
کے دائمی طور پر قیام کا یہ بھی ایک ذریعہ ہے کہ اس میں یسری یعنی احکام شریعت میں سے
676
Page 685
زیادہ سہل کو مدنظر رکھا گیا ہے...قرآن کریم میں کوئی ایسی تعلیم نہیں جس میں فطرت انسانی
کے کسی پہلو کو نظر انداز کیا گیا ہو یا کوئی ایسی تعلیم دی گئی ہو جس پر عمل کرنا لوگوں کو بارِ خاطر
معلوم ہو بلکہ اس کی تعلیم انسانی فطرت کے مطابق ہے اور اس میں ایسی سہولتیں موجود ہیں جن کی
وجہ سے ہر فطرت کا انسان اس کے احکام پر عمل کر سکتا ہے.یہ ٹینری قرآن کریم ہے.کیا بلحاظ اس کے کہ اس کو حفظ کرنا نہایت آسان ہے اور کیا
بلحاظ اس کے کہ عمل کرنا نہایت آسان ہے.یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے جس کا جواب دینا نہایت ضروری ہے اور وہ یہ کہ اسلام
میں تو روزانہ پانچ نمازیں پڑھنے کا حکم ہے اور عیسائیوں میں ہفتہ میں صرف ایک دن تھوڑی
دیر کے لئے عبادت کرنے کا حکم ہے.اب بتاؤ ان دونوں میں سے کون سی تعلیم آسان
ہوئی ؟ اسلام کی جس میں روزانہ پانچ وقت نمازیں پڑھنے کا حکم ہے یا عیسائیت کی جس میں ہفتہ
میں صرف ایک دن تھوڑی دیر کے لئے عبادت کرنے کا حکم ہے؟ اس کے متعلق یاد رکھنا
چاہئے کہ یسری ایسی چیز کو بھی کہتے ہیں جو خواہ جسمانی طور پر تکلیف دہ ہو لیکن روحانی طور پر
انسان کے لئے نہایت فرحت بخش ہو.اسلام میں گوروزانہ پانچ وقت نمازیں پڑھنے کا حکم ہے مگر چونکہ نماز میں انسان
کا اپنا روحانی
فائدہ ہے اس لئے پانچ نمازیں پڑھنا اُس کے لئے آسان ہو جائے گا بہ نسبت اس ایک نماز
کے جو ہفتہ میں صرف ایک دن پڑھنی پڑے.مومن کہے گا کہ میرے لئے یہ پانچ نمازیں
به نسبت ہفتہ والی صرف ایک نماز کے زیادہ آسان ہیں کیونکہ صرف ایک نماز کے نتیجہ میں میرا
خدا مجھ سے چھوٹ جاتا ہے اور پانچ نمازوں کے نتیجہ میں میرا خدا مجھ سے مل جاتا ہے.پس
یسری سے مراد ظاہری آسانی نہیں بلکہ روحانی فوائد کے اعتبار سے آسانی مراد ہے کہ جب
انسان روحانی فائدہ دیکھتا ہے تو عمل اُس کے لئے آسان ہو جاتا ہے.وَنُيَتِرُكَ لِلْيُسْری کے ایک یہ بھی معنے ہیں کہ ہم تجھے ایسی تعلیم دیں گے جس میں
677
Page 686
صرف احکام ہی نہیں ہوں گے بلکہ اُن احکام کے ساتھ ساتھ اُن کی حکمتیں بھی بیان ہوں گی اس
لئے وہ احکام بجائے گراں گزرنے کے بالکل آسان معلوم ہوں گے اور لوگ اُن کو چھوڑ نا پسند
نہیں کریں گے.یہ ایک قدرتی بات ہے کہ جب کسی حکم کی حکمت بیان کر دی جائے اور
انسان پر یہ واضح ہو جائے کہ یہ حکم میرے فائدہ کے لئے دیا گیا ہے تو جس شوق سے وہ حکمت
معلوم کرنے کے بعد عمل کرتا ہے اُس شوق سے وہ حکمت معلوم کئے بغیر عمل نہیں کرسکتا.یہی
بات اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمائی ہے کہ ہم نے ہر حکم کی حکمت بیان کر دی ہے اور
اس وجہ سے اس تعلیم پر عمل لوگوں کے لئے نہایت آسان ہو گیا ہے.غرض وَنُيَشرُكَ لِلْيُسْری کے تین معنے ہوئے.یہ بھی کہ ہم نے اس قرآن کا حفظ کرنا
آسان کر دیا ہے.یہ بھی کہ ہم نے احکام کے ساتھ ان کی حکمتیں بھی بیان کر دی ہیں جس کی وجہ
سے لوگوں کے لئے عمل آسان ہو گیا ہے.اور یہ بھی کہ ہم نے ایسی تعلیم نازل کی ہے جس میں ہر
فطرت کا لحاظ رکھا گیا ہے اور ضرورت کے مطابق اُس میں لچک پیدا ہو جاتی ہے.چنانچہ
شریعت اسلامیہ کے تمام احکام کو دیکھ لو اسلام نے کسی ایک حکم کے متعلق بھی یہ نہیں کہا کہ
اس میں حالات کے لحاظ سے کوئی تبدیلی نہیں کی جاسکتی.نماز کے متعلق اسلام نے نہایت ہی
تاکیدی احکام دیتے ہیں.لیکن اگر کوئی شخص بیہوش ہو جائے تو اس کے لئے کوئی حکم نہیں رہتا.اگر کوئی شخص پاگل ہو جائے تو اس کے لئے یہ حکم نہیں ہوگا کہ وہ بھی نماز پڑھے.بلکہ اگر کوئی
شخص نماز پڑھتے پڑھتے پاگل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ جب تک پاگل رہے ایسا ہی
سمجھا جائے گا جیسے وہ نماز پڑھتا رہا ہے اور اُسے وہی ثواب ملے گا جو نماز پڑھنے والوں کو ملتا
ہے.غرض کوئی مشکل ایسی نہیں جس کا علاج اسلام میں موجود نہ ہو....پس بے شک قرآن کریم میں بعض احکام بظاہر مشکل معلوم ہوتے ہیں مگر ان مشکل احکام کو
با حکمت بنا کر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لئے آسان کر دیا ہے اور پھر ان احکام کو لچک دار بنایا ہے
جس میں ضرورت کے وقت کئی قسم کی تبدیلیاں ہو جاتی ہیں اور ہر فطرت کا انسان آسانی سے اُن
678
Page 687
پر عمل کر سکتا ہے اور یہ بھی اسلام کی حفاظت اور اُس کے دائمی طور پر قیام کا ایک ذریعہ ہے.فَذَكِرانْ تَفَعَتِ الذِكُرُى
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب ہم نے ایسی کامل تعلیم دی ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے اور
جس کی قیامت تک حفاظت کی جائے گی تو اب تیرا کام یہ ہے کہ تولوگوں کو نصیحت کر.جبکہ یہ
یقینی بات ہے کہ نصیحت لوگوں کو فائدہ دیتی ہے.ا فذكر ان نَفَعَتِ الکری کے یہ معنے نہیں ہیں کہ ایک دفعہ نصیحت کرو اور کوئی نہ
مانے تو اُسے چھوڑ دو.اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَذَكر ان نَفَعَتِ الذِ گری جب کہ یہ یقینی اور تحقیقی
بات ہے کہ ذکری سے ہمیشہ نفع پہنچتا ہے تو پھر اے محمد رسول اللہ صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم تو
ذکری کو چھوڑ یو نہیں بلکہ دن اور رات اس میں مشغول رہیں.اگر آج نہیں تو کل اور کل نہیں تو
پرسوں ان لوگوں کے سینے گھل جائیں گے اور یہ ہدایت کو قبول کرلیں گے.پس یہاں یہ حکم
نہیں دیا گیا کہ ایک دو دفعہ نصیحت کرو، اگر فائدہ نہ ہو تو چھوڑ دو.بلکہ حکم یہ دیا گیا ہے کہ ہمیشہ
نصیحت کرتے جاؤ کیونکہ نصیحت ایسی چیز ہے جو ضرور دل پر اثر کرتی ہے.وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الذِي يَصْلَى النَّارَ الكُبرى.اوپر کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون بیان فرمایا تھا کہ نصیحت کو بالالتزام جاری
رکھنا چاہئے.کیونکہ خشیت کے اوقات انسانی قلب پر آتے رہتے ہیں اور ہو سکتا ہے جو شخص
آج انکار کر رہا ہو وہ کل ہماری باتوں کو تسلیم کرنے لگ جائے.اس آیت میں اللہ تعالیٰ بیان
فرماتا ہے کہ اگر تم ہمارے اس حکم پر عمل جاری رکھو تو پھر ایسا ہی شخص ہدایت پانے سے محروم
رہ سکتا ہے جو سخت شقی ہو اور جس کے گناہوں کی وجہ سے خدا تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا ہو کہ اب
اسے ہدایت نہیں مل سکتی اور نہ اور لوگ ضرور مان جائیں گے.یہ علیحدہ سوال ہے کہ وہ جلدی
مانتے ہیں یادیر کے بعد مانتے ہیں.یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آشفی کا لفظ کیوں استعمال فرمایا ہے.اس کا
679
Page 688
جواب یہ ہے کہ چونکہ رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہیں اس لئے آپ کا منکر
بھی تمام انبیاء کے منکرین میں سے زیادہ شقی اور بد بخت ہے.مولی کا منکر صرف شقی ہے.عیسی
کا منکر صرف شقی ہے.ابراہیم کا منکر صرف شقی ہے.داؤد اور سلیمان کا منکر صرف شقی ہے مگر
محمد رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کا منکر آشفی ہے.کیونکہ آپ تمام انبیاء سابقین سے زیادہ بلند
درجہ رکھنے والے ہیں اور آپ جو ہدایت لائے وہ بھی تمام ہدایتوں سے افضل اور بلند تر ہے.دوسرے آشفی کا لفظ...یہ بتانے کے لئے بھی استعمال کیا گیا ہے کہ ہدایت سے محروم صرف
بڑاشقی ہوتا ہے ورنہ عام شقی بھی کسی وقت ہدایت پا جاتا ہے.چونکہ اس شخص نے سب سے بڑے نبی کا انکار کیا تھا اس لئے اس مناسبت کی بناء پر
فرمایا کہ ایسے شخص کو سب سے بڑی آگ میں داخل کیا جائے گا یا با وجود بار بار کی اور پوری
تبلیغ کے نہ مانا اس لئے اشد ترین بھڑکنے والی آگ میں داخل کیا جائے گا.ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيى
وہ مرے گا اس لئے نہیں کہ زندہ رہے گا اور زندہ اس لئے نہیں ہوگا کہ زندگی اس کو کہتے
ہیں جس میں اطمینان اور آرام اور سکون حاصل ہو.اُسے چونکہ انتہائی تکلیف ہوگی اس لئے اس
کے زندہ ہونے کو زندگی نہیں کہا جائے گا.اس کی ایسی ہی مثال ہے جیسے کسی سخت بیمار سے
دریافت کیا جائے کہ تمہارا کیا حال ہے؟ تو وہ کہتا ہے میرا حال کیا پوچھتے ہو ئیں نہ مرتا ہوں نہ
جیتا ہوں.یعنی میں مرا تو نہیں کیونکہ جی رہا ہوں.مگر میں جیتا بھی نہیں کیونکہ زندگی سخت تکلیف
سے کٹ رہی ہے.اسی طرح فرماتا ہے ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يحيى عذاب اتنا شدید ہوگا کہ
نہ تو وہ مر کر اس سے چھٹکارا حاصل کر سکیں گے اور نہ زندہ رہ کر اس کو برداشت کرنے کی طاقت
رکھیں گے ان کی زندگی موت سے بدتر ہوگی.قَد أَفْلَحَ مَنْ تَزَلي
ترکی کے معنے پاک ہونے کے ہوتے ہیں.پس اس آیت کے یہ معنے ہیں کہ وہ
شخص کامیاب ہوا جس نے تقدس کا جامہ پہن لیا.اللہ تعالیٰ چونکہ خود قدوس ہے اس لئے وہی
680
Page 689
شخص اس کا قرب حاصل کر سکتا ہے جو تقدس اور پاکیزگی اپنے اندر پیدا کرتا ہے.گناہ آلود
زندگی بسر کرنے والے، خدا تعالیٰ کے احکام کو پس پشت ڈالنے والے، شیطانی راہوں کو
اختیار کرنے والے اور نفسانی خواہشات کے پیچھے چلنے والے دنیا میں بھی ذلیل ہوتے ہیں اور
آخرت میں بھی ذلیل ہوں گے.تمام کامیابیوں کی جڑ پاکیزگی اختیار کرنا ہے.وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى
ذكر اسم ربّہ کے معنے صرف یہی نہیں کہ انسان منہ سے کہتا رہے کہ الْحَمْدُ لِلهِ
سبحان الله الله اكبر - یا آج کل کے نام نہاد مسلمانوں کی طرح جو ذکر الہی کی اہمیت اور اس
کے طریق سے ناواقف ہوتے ہیں صرف اللہ اللہ کہتا رہے بلکہ اس کے معنے یہ ہیں کہ خدا
انسان کو ہر وقت یادر ہے.چنانچہ فصلی کا لفظ جو اس کے ساتھ ہی استعمال ہوا ہے بتا رہا ہے
کہ ذکر سے مراد محض الفاظ کی رٹ لگانا نہیں بلکہ اس سے مراد وہ ذکر ہے جس کے نتیجہ میں نماز
پڑھی جاتی ہے.اگر منہ سے کہنے والی بات ہی مراد ہوتی تو وہ تو خود بخود نماز میں آجاتی ہے اس
کے علیحدہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی.مگر اللہ تعالیٰ کا ذکر اشتم ربّہ کا پہلے ذکر کرنا اور
فصلی کو بعد میں رکھنا بتا رہا ہے کہ یہ وہ ذکر ہے کہ جس کے بعد نماز پڑھی جاتی ہے یعنی انسانی
قلب پر خدا تعالیٰ کی محبت اس قدر غالب ہو کہ وہ بے چین ہو کر کھڑا ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی.عبادت میں مشغول ہو جائے.پھر خدا کی محبت کا شعلہ اس کے دل میں بھڑک اٹھے اور وہ اپنے
محبوب کے سامنے سر بسجود ہو جائے گویا ایک دیوانگی اور وائٹنگی اس پر طاری ہو.خدا تعالیٰ کا
ذکر اس کی غذا ہو اور اس کی یاد اُس کے دل میں اس طرح بار بارتازہ ہو کہ وہ اس بات پر مجبور ہو
جائے کہ خدا تعالیٰ کی عبادت کرے اور اپنی محبت کے جذبات کا ہدیہ اُس کے سامنے پیش
کرے.گویا اس ذکر سے مراد محض منہ سے اللہ اللہ کہنا نہیں بلکہ وہ عملی حالت مراد ہے جو
اللہ تعالیٰ کے عشق پر دلالت کرتی ہے اور جس کے نتیجہ میں نماز اور عبادت پیدا ہوتی ہے.(ماخوذ از تفسیر کبیر زیر تفسیر سورۃ الاعلی )
681
Page 690
سَبْحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى الَّذِي خَلَقَ فَسَوَى وَالَّذِي قَدَّرَ
فَهَدى (الا على 4,2)
حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے خطبہ جمعہ فرمودہ 14 مئی
2010ء میں فرمایا:
یہ آیات جو میں نے تلاوت کی ہیں.سورۃ اعلیٰ کی پہلی تین آیات ہیں.یعنی بسم اللہ کے
علاوہ.اس سورۃ کو جیسا کہ ہمارے ہاں عموماً طریق رائج ہے، جمعہ اور عیدین میں پہلی رکعت
میں پڑھا جاتا ہے.کیونکہ حدیث میں روایت ملتی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ اور
عیدین پر پہلی رکعت میں سورۃ اعلیٰ پڑھا کرتے تھے.اسی طرح دوسری رکعت میں سورۃ
الغاشیہ پڑھا کرتے تھے.(مسلم کتاب الجمعۃ باب ما يقر آفى صلوۃ الجمعۃ حدیث نمبر 1912)
پس یہ اس سنت کی پیروی ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جس کی وجہ سے یہ
سورتیں پڑھی جاتی ہیں.اسی طرح یہ بھی روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم وتروں کی پہلی رکعت میں سورۃ اعلیٰ
پڑھا کرتے تھے.اور دوسری رکعت میں سورۃ الکافرون اور تیسری رکعت میں بعض روایات
میں آتا ہے سورۃ الاخلاص اور بعض میں یہ ہے کہ آخری تین سورتیں.آخری دوقل اور سورۃ
اخلاص.( ترمذی ابواب الوتر باب ما جاء في ما يقر آب فى الوتر حدیث نمبر 462 463)
رض
بہر حال اس وقت سورۃ الاعلیٰ کی ان آیات کے حوالے سے کچھ کہوں گا.حضرت مصلح موعود
نے تفسیر کبیر میں اس کی بڑی تفصیل سے تفسیر بیان کی ہے اور بحث فرمائی ہے.حضرت
مصلح موعود کی تفاسیر جو ہیں وہ بھی ایک عظیم علمی خزانہ ہیں.گو یہ پوری قرآن کریم کی تو تفسیر
نہیں ہے لیکن جن جن سورتوں کی ہے اُن کو پڑھنے کی طرف جماعت کو توجہ کرنی چاہئے.یہ
مختلف دس جلدیں ہیں.682
Page 691
سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (الا علی 2) یعنی تسبیح کر اپنے رب کی جو اعلیٰ ہے.یعنی تیرا رب جو
ربوبیت کے لحاظ سے سب سے بلند اور اعلیٰ شان رکھتا ہے اُس کی تسبیح کر.اس کا یہ مطلب بھی
ہے کہ تو اپنے رب کا نام دنیا میں بلند کر.گویا دو ذمہ داریاں ایک مومن کی لگائی گئی ہیں جو اس
بات پر یقین رکھتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ
نے ہمارے لئے کامل نمونہ بنایا اور آپ پر شریعت کامل ہوئی اور آپ کے طریق پر چلنا ہم پر
فرض قرار دیا.پس ہر شخص جو آپ کی طرف حقیقی رنگ میں منسوب ہوتا ہے اور ہونا چاہتا ہے،
اس کا یہ فرض ہے کہ آپ کے اُسوہ پر چلنے کی کوشش کرے.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ
لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (سورة الاحزاب (22).یقیناً تمہارے لئے اللہ
کے رسول میں ایک کامل نمونہ ہے جس کی پیروی کرنی چاہئے.اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے
میں آپ کا کیا نمونہ تھا؟ آپ کے صبح شام، رات دن اللہ تعالیٰ کے ذکر سے پر گزرتے تھے.پھر بھی آپ فرماتے ہیں کہ اے رب ! مجھے اپنا ذ کر کرنے والا اور اپنا شکر کرنے والا بنا.( سنن ابن ماجہ کتاب الدعاء باب دعاء رسول الله على العلم حدیث نمبر 3830)
رکوع اور سجدے میں آپ اللہ تعالیٰ کی تسبیح وتحمید فرماتے تھے.اور آپ
کی تسبیح وتحمید اور
گریہ وزاری ایک عجیب رنگ رکھتی تھی.رکوع میں جب سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِیم سے اپنے عظیم
رب جورب العالمین ہے، اس کی بزرگی اور برتری کا ذکر فرماتے ہیں تو کھڑے ہو کر سمیع الله
لمن حمدہ کہہ کر پھر اللہ تعالیٰ کی بے شمار حد کی طرف توجہ فرماتے ہیں.آپ کے رکوع اور
سجود اور قیام اور نماز کی ہر حرکت کے بارہ میں ایک دفعہ پوچھنے پر حضرت عائشہ نے فرمایا تھا
کہ اس کی خوبصورتی اور لمبائی نہ پوچھو.( بخاری کتاب التهجد باب قیام النبی الالمام باليل في رمضان وغیرہ حدیث نمبر 1147)
رض
سجدوں کی لمبائی کے بارہ میں ایک روایت میں یہ ذکر ملتا ہے.حضرت عبدالرحمن بن عوف
کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد میں تشریف لائے اور قبلہ رو ہو کر سجدہ میں
چلے گئے.بہت لمبا سجدہ کیا.اتنا لمبا کہ میں آپ کو دیکھ کر پریشان ہو گیا.بلکہ یہاں تک
683
Page 692
میری پریشانی بڑھی کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح قبض کرلی ہے.اس
پریشانی کی حالت میں میں آپ کے قریب پہنچا تو آپ سجدہ سے اٹھ بیٹھے.آپ نے فرمایا
کہ کون ہے؟.میں نے عرض کی یا رسول اللہ ! میں عبد الرحمن ہوں.پھر میں نے عرض کیا کہ
اے اللہ کے رسول ! آپ کا یہ سجدہ اتنا زیادہ لمبا ہو گیا تھا کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں آپ کی
روح تو قبض نہیں ہوگئی.آپ نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل آئے تھے اور یہ خوشخبری دی تھی
کہ اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں فرماتا ہے کہ جو آپ پر درود بھیجے گا اس پر میں رحمتیں نازل کروں
گا.اور جو سلامتی بھیجے گا اس پر میں سلامتی نازل کروں گا.اس بات پر میں سجدہ شکر بجالا رہا تھا
اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح وتحمید کر رہا تھا.( مسند احمد بن حنبل جلد 1 صفحہ 512-513 حدیث نمبر 1664 : مسند عبد الرحمن بن عوف مطبوعہ بیروت ایڈیشن 1998ء)
یہی نہیں کہ آپ پر اللہ تعالیٰ کا یہ اتنا بڑا انعام تھا اس کی وجہ سے شکر بجالا رہے ہیں، بلکہ ہر
چھوٹی سے چھوٹی اللہ تعالی کی جو نعمت تھی ، اس پر بھی آپ اللہ تعالیٰ کی بے انتہا تسبیح وحمد و
شکر گزاری فرمایا کرتے تھے.آپ کی خوراک کیا تھی.بعض وقت تو فاقے بھی ہوتے تھے
اور روکھی سوکھی روٹی ہوتی تھی.لیکن اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر فرماتے تھے.اور
تسبیح سے اپنی زبان کو تر رکھتے تھے.یہاں یہ بھی بتا دوں کہ روایت میں آتا ہے کہ سبح اسم ربك الْأَعْلَى (الاعلیٰ 2) کی آیت
اترنے سے پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی یہ دعا کرتے اور اپنے صحابہ کو بھی آپ نے فرمایا
ہوا تھا کہ سجدے میں یہ دعا پڑھا کرو کہ اللهم لك سجدت لیکن اس آیت کے بعد پھر آپ نے
سُبْحَانَ رَبِّي الأعلیٰ کی دعا سکھائی.اسی طرح فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظیم کی آیت جب نازل
ہوئی ہے تو پھر آپ نے رکوع میں بھی سُبحان ربی العظیم کی دعا سکھائی ہے.( ابوداؤد کتاب الصلوۃ باب ما يقول الرجل في ركوع و سجودہ حدیث نمبر 869، 871)
آپ نے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنے کے طریق کس طرح سکھائے ؟ کس طرح ہر وقت آپ
کے دل میں اللہ تعالیٰ کی بزرگی اور برتری کا خیال رہتا تھا اور آپ راہنمائی فرماتے تھے؟ اس
684
Page 693
رض
بارے میں ایک روایت میں حضرت جویریہ بیان کرتی ہیں کہ صبح کی نماز کے وقت آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گئے.اس وقت میں مصلے پر بیٹھی تھی اور دن چڑھے جب
آپ واپس آئے تو میں اس وقت بھی مصلے پر بیٹھی تھی اور ذکر کر رہی تھی اور تسبیح کر رہی تھی.تو
آپ نے پوچھا تم صبح سے اس حال میں یہاں بیٹھی کیا کر رہی ہو؟ میں نے عرض کی کہ میں تسبیح کر
رہی ہوں.اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہی ہوں.آپ نے فرمایا اس کے بعد جب سے میں یہاں سے
گیا ہوں اور اب آیا ہوں میں نے صرف چار کلمات تین دفعہ دہرائے ہیں.اگر ان کلمات کا
مواز نہ میں تمہارے اس سارے وقت کے ذکر اور تسبیح سے کروں تو میرے کلمے جو ہیں وہ بھاری
ہیں.جو یہ ہیں.کہ سُبحانَ اللهِ عَدَدَ خَلْقِهِ سُبْحَانَ اللهِ رِضَاءَ نَفْسِهِ سُبْحَانَ اللهِ زِنَةَ عَرْشِهِ
سُبْحَانَ اللهِ مِدَادَ كَلِمَاتِه.(مسلم کتاب الذكر والدعاباب التسبيح اول النهار وعند النوم 6807: 6808)
اللہ پاک ہے اس قدر جتنی اس کی مخلوق ہے.اللہ پاک ہے جس قدر اس کی ذات یہ بات
پسند کرتی ہے.اللہ پاک ہے جس قدر اس کے عرش کا وزن ہے یعنی بے انتہا پاک ہے اور اللہ
پاک ہے جس قدر اس کے کلمات کی سیاہی ہے.ایک تو اس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسی سے آپ کی ازواج کی تسبیح وتحمید
اور ذکر سے رغبت اور اس کے لئے کوشش کا پتا چلتا ہے کہ کس قدر انہماک سے اور کتنی دیر
تک یہ دعائیں اور ذکر فرمایا کرتی تھیں.پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تسبیح کا اندازہ ہوتا
ہے.آپ نے جس غور اور جس گہرائی سے یہ تسبیح کی اس کا اندازہ لگائیں کہ ایک لمبے عرصے
میں جو کم از کم گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹے پر تو محیط ہوگا، اس میں آپ نے صرف تین مرتبہ یہ الفاظ
دہرائے.یہ تو آپ کا ہی مقام تھا.لیکن توجہ دلائی کہ تسبیح ان جامع الفاظ میں کرو اور ساتھ ساتھ
غور کرو.اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرتے ہوئے ، اللہ تعالیٰ کی عظمت و جبروت کو سامنے
رکھتے ہوئے تسبیح کرو.پھر جب فتح مکہ ہوئی تو اس تسبیح اور شکر گزاری کا ایک اور انداز دیکھیں کہ اونٹنی پر بیٹھے ہیں.685
Page 694
سر جھک کر پالان سے چھورہا تھا اور سجدہ شکر بجا لاتے ہوئے یہ دعا آپ پڑھ رہے تھے کہ
سُبْحَانَكَ اللهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْلِي کہ اے اللہ ! تو پاک ہے اپنی حمد اور
تعریف کے ساتھ.اے اللہ مجھے بخش دے.یہ معیار حاصل کرنے کے بعد جب خدا تعالیٰ نے آپ کی امت کے افراد سے اپنی محبت کو
بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے ساتھ مشروط کیا ہے.تو پھر بھی آپ اللہ تعالیٰ کی
تسبیح وتحمید کے ساتھ ، شکر گزاری کے ساتھ اپنی مغفرت طلب فرما رہے ہیں.پس یہ آپ کے
نمونے ہیں.انفرادی طور پر بھی تسبیح و تحمید کے طریق سکھا رہے ہیں تا کہ اللہ تعالیٰ کی بزرگی اور
تقدیس کا اظہار حقیقی رنگ میں کرنے کا پتہ چلے.آپ کے لئے امت کے درود اور سلامتی بھیجنے
پر تسبیح اور حمید اور شکر گزاری کا وہ اظہار فرمایا کہ جس کی مثال نہیں مل سکتی.ایک شکر گزاری اس
لئے کہ خدا تعالیٰ نے مجھ پر درود بھیجنے کو اس قدر اہمیت دی ہے کہ یہ امت کے لئے بخشش کا
سامان ہو گیا ہے.اور ایک اللہ تعالیٰ کی تسبیح اس لئے کہ کس کس طرح اللہ تعالیٰ میری امت کو
بخشنے کے سامان فرما رہا ہے.اور کیا مقام اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرما رہا ہے؟ پھر جب اللہ تعالیٰ
نے فتح مکہ کی صورت میں کامیابی عطا فرمائی تو تسبیح و تحمید اور شکر گزاری کا وہ اعلیٰ نمونہ ہے اور
عاجزی کا وہ اعلیٰ نمونہ ہے جس کی مثال نہیں ملتی.یعنی یہ سب تسبیح کے نمونے دکھا کر اور سکھا کر
امت کو اس طرف متوجہ فرمایا ہے کہ تمہاری بقا اور تمہاری کامیابی اور تمہاری ترقی اور تمہاری
فتح بھی اسی میں ہے کہ دنیاوی اسباب پر بھروسہ نہ کرو بلکہ رب اعلیٰ کی تسبیح اور تحمید کروجو
رب العالمین ہے.یاد رکھو بے شک اپنے اپنے رنگ میں بعض اور بھی رب ہیں جن سے تمہیں
واسطہ پڑتا رہتا ہے.شروع میں ، ابتدا میں انسان جب بچہ ہوتا ہے، بچے کی پرورش میں بھی
اس کے ماں باپ حصہ لیتے ہیں.اس لحاظ سے وہ بھی رب کہلاتے ہیں.پھر اس کے بعد بڑا
ہوتا ہے اور دنیاوی کاموں میں پڑتا ہے.افسران ہیں ، بادشاہ ہیں ہلکی سر براہ ہیں جو ایک طرح
سے پرورش میں حصہ لیتے ہیں.لیکن ان سب کی ربوبیت جو ہے وہ نقائص سے پُر ہے، کامل
نہیں ہے.ماں ہے جو سب سے زیادہ خالص ہو کر بچے کی پرورش کر رہی ہوتی ہے لیکن اس
686
Page 695
میں بھی کاملیت نہیں ہے، اس لئے اس کی پرورش میں کمیاں رہ جاتی ہیں.کبھی بچے کو زیادہ
کھلا دیا تو وہ بیمار ہو گیا.کبھی خوراک کا خیال نہ رکھا تو کمز ور ہو گیا.کبھی کسی اور طرف تو جہ ہوگئی تو
بچے کی نگہداشت صحیح طرح نہ ہوسکی.کبھی کسی چیز میں کمی رہ جاتی ہے، کبھی کسی چیز میں.اسی طرح
تمام دنیاوی افسران ہیں یا ملازمین کے مالک ہیں، وہ سب کمزور ہیں.اور پھر وہ لوگ یہ تو
چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے لیکن تعریف وہ کروانا چاہتے ہیں جس پر وہ کبھی پورا نہیں
اترتے اور یوں اکثر جھوٹی تعریفیں اور خوش آمدیں کرنی پڑتی ہیں.جس سے انسان کی طبیعت
میں جھوٹی خوش آمدیں کر کے، تعریفیں کر کے بعض دفعہ منافقت بھی پیدا ہو جاتی ہے.لیکن
رب اعلیٰ وہ ہے جو ہر عیب سے پاک ہے.جس کی تعریف حقیقی ہے.جس نے رحمانیت کے
جلوے دکھاتے ہوئے بھی پرورش کے انتظام کئے ہیں.اور جو رحیمیت کے جلوے دکھاتے
ہوئے بھی اپنے بندوں کے لئے بے انتہا فضل نازل فرماتا ہے.دعاؤں کو سنتا ہے، وہ مجیب
بھی ہے.غرض کہ اس کے بے انتہا اور بھی صفاتی نام ہیں جس کے مطابق وہ اپنے بندوں سے
سلوک بھی کرتا رہتا ہے.پس ایک مومن کو چاہئے کہ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (الاعلیٰ 2) پر
عمل کرتے ہوئے اس کامل صفات والے اعلیٰ رب کی تسبیح کرتا رہے اور اس کی خیر کی تمام
صفات سے حصہ لینے کی کوشش کرے اور اس کی ناراضگی اور پکڑ سے بچنے کی کوشش کرے.ہر خیر کے ساتھ شر بھی ہوتا ہے.اللہ تعالیٰ سے تمام قسم کے شرور سے بچنے کی دعا کرنی چاہئے اور
حقیقی تسبیح کرنے والے کو اللہ تعالیٰ یقیناً اپنی پناہ میں لے لیتا ہے.قرآن کریم میں تسبیح کے ذکر میں جو بیان ہوا ہے اس میں نمازوں کو بھی تسبیح کے ساتھ
ملایا گیا ہے.یعنی نمازیں بھی ایک قسم کی تسبیح ہیں.پس ان کی پابندی کرنا اور باقاعدگی سے ادا
کرنا یہ بھی ضروری ہے.تبھی تسبیح انتم ترتيك الأخلی کا صیح اوراک حاصل ہوگا.پھر جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اپنے رب کے نام کو
دنیا میں بلند کرنا.اپنے رب کے نام کو دنیا میں بلند کرنا ، یہ بھی حکم ہے.اس بارے میں جب سب
سے اوّل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہم دیکھتے ہیں تو اس کے بھی اعلیٰ ترین نمونے
687
Page 696
آپ نے ہی قائم فرمائے.آپ نے دعوت الی اللہ کا حق قائم فرما دیا.جب اللہ تعالیٰ نے
آپ کے بارہ میں فرمایا کہ داعيا الى اللہ پاڈیہ (سورۃ الاحزاب 47) کہ اللہ تعالیٰ کے حکم
سے آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا گیا ہے.اور جب آپ کو فرمایا کہ
يَأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلّغ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ (المائدة68) کہ اے رسول! تیری طرف
تیرے رب کی طرف سے جو کلام اتارا گیا ہے اسے لوگوں تک پہنچا تو اس کا بھی آپ نے حق
ادا کر دیا.کیونکہ اس کے بعد رب اعلیٰ کے نام کی سر بلندی جو پہلے ہی آپ کا مقصود تھی اس میں
اور زیادہ اضافہ ہو گیا.نرمی سے ، حکمت سے، احسان سے، احسان کرتے ہوئے اور صبر دکھاتے
ہوئے آپ نے ہر حالت میں تبلیغ کے کام کے حق کو ادا کرنے کی کوشش فرمائی.ہر حال
میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہوئے اس حق کو ادا کیا.مشکلات بھی آئیں تو تب بھی اللہ تعالیٰ
کی تسبیح کرتے ہوئے آپ کے قدم آگے ہی بڑھتے چلے گئے.کوئی خوف ، کوئی ڈر آپ کو
اس کام سے روک نہیں سکا.آپ کی قوت قدسی نے یہی روح صحابہ میں بھر دی تھی.اللہ تعالیٰ
کے نام کی سربلندی کے لئے وہ بھی قربانیاں دیتے چلے گئے.پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الَّذِی خَلَقَ فَسَوى (الاعلیٰ (3) یعنی جس نے پیدا کیا پھر
ٹھیک ٹھاک کیا.اس کے یہ معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس حالت میں پیدا کیا ہے کہ
اس کے اندر تمام ضروری طاقتیں رکھی ہیں اور ترقی کے مادے اس میں موجود ہیں.عموماً ایک
نارمل بچے کی جب پیدائش ہوتی ہے تو اس میں تمام ضروری طاقتیں بھی موجود ہوتی ہیں.اور جوں
جوں اس کی نشو ونما ہوتی رہتی ہے اور جس طرح پہلے زمانوں میں بھی ہوتی رہی ان طاقتوں میں
اس ماحول کے لحاظ سے نکھار پیدا ہوتا چلا جاتا ہے.بیشک بعض ذہنی اور جسمانی لحاظ سے
کمز ور بھی ہوتے ہیں لیکن یہ عمومی حالت نہیں ہے.پس انسان کو جب اشرف المخلوقات بنایا تو
اس میں ذہنی صلاحیتیں بھی ایسی رکھیں کہ اگر ان کو صحیح طور پر استعمال کیا جائے تو تمام مخلوق کو وہ
زیر کر لیتا ہے.گویا انسان اللہ تعالیٰ کی صفات کا پر تو بن سکتا ہے.اور جیسا کہ پہلے بھی میں ذکر
کر چکا ہوں اس کا کامل نمونہ ہمارے آقا و مولیٰ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن پر
688
Page 697
اللہ تعالیٰ نے اپنی کامل تعلیم اتاری اور اس مزاج کے مطابق اتاری جو انسان میں خدا تعالیٰ نے
پیدا فرمایا ہے یا جس کی نشو نما اس زمانے میں ہو چکی تھی اور آئندہ بھی انسان کی ذیلی صلاحیتوں
کا اور اس کے قویٰ کا نشود نما اب قیامت تک ہوتے چلے جانا ہے.انسان کی فطرت میں اگر
اللہ تعالیٰ نے نرمی اور غصہ رکھا ہے تو یہ بھی عین ضرورت کے مطابق ہے.کبھی نرمی کا اظہار ہو
جاتا ہے، کبھی غصہ کا اظہار.اس لئے قرآن کریم میں جو تعلیم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر
اتاری گئی ہے اس میں بھی یہی فرمایا ہے کہ غصے کا اور نرمی کا اظہار اپنے وقت پر کرو تبھی ان
انسانوں میں شامل ہو گے جو سوی کے لفظ کے تحت آتے ہیں.یعنی جب ہر عمل جو ہے موقع
اور محل کے مطابق ہو.مثلاً اگر اصلاح کی ضرورت ہے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کے لئے معاف
کرنے میں اصلاح کا پہلو نکلتا ہے یا سزا دینے میں.اگر صرف ہر صورت میں معاف ہی کیا
جاتارہے تو معاشرے میں ان لوگوں کے ہاتھوں جو ہر وقت فساد پر محلے رہتے ہیں معاشرے کا
امن برباد ہی ہوتا چلا جائے گا.پس ایک عقل مند اور اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت رکھنے والا انسان
ہمیشہ اعتدال سے کام لیتا ہے.اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اس کو اس طرح پیدا
کیا ہے جو ہر لحاظ سے مناسب ہے.عیب سے پاک ہے.پھر عقلمند انسان کا ہر عمل اور فعل،
موقع اور محل کے مناسب حال ہوتا ہے.خَلق فسوى الاعلیٰ (3) کا یہ مطلب بھی ہے کہ اس میں جب خرابیاں پیدا ہوتی ہیں تو اس
عیب کو درست کرنے کے لئے بھی خدا تعالیٰ سامان پیدا فرماتا ہے.بیماریاں ہیں تو ان کا
علاج ہے اور یہ علاج کے طریق بھی خدا تعالیٰ ہی سکھاتا ہے.بعض دہر یہ یہ خیال کرتے ہیں
کہ شاید ان کی دماغی صلاحیتوں کی وجہ سے انہیں علاج سمجھ آ گیا لیکن حقیقت یہی ہے کہ اس
کے پیچھے سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کارفرما ہے.اور یہ باتیں پھر اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی طرف
اشارہ کرتی ہیں.انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا ذہن عطا فرمایا ہے کہ وہ اپنی ضروریات کے لئے،
سہولیات کے لئے ایجادات کرتا چلا جا رہا ہے.مثلاً بیماریوں کے خلاف علاج ہے تو اس کے
بھی نئے نئے طریق نکال رہا ہے.بہت سی بیماریاں جو پہلے نہیں ہوتی تھیں یا پتہ نہیں تھا، جن
689
Page 698
کی صلاحیت نہیں تھی جب اللہ تعالیٰ نے صلاحیت پیدا کی ، انسان کی نشو نما کی.اس کی ذہنی
اور جسمانی طاقتیں بڑھائیں تو بعض ایسی نئی نئی باتیں بھی اس کے ذہن میں پیدا ہوگئیں جن کو
استعمال کر کے وہ اپنی زندگی کو مزید بہتر بنا سکتا ہے.مثلاً دل ہے انسان کا.پہلے تو کسی کو پتہ ہی
نہیں لگتا تھا یا انسانی زندگی اتنی سخت تھی کہ ورزش کی وجہ سے اور اپنی دوسری مصروفیات کی
وجہ سے اور ایسی خوراک ہونے کی وجہ سے جو دل کو نقصان نہیں پہنچاتی ، دل کی بیماریاں نہیں
تھیں لیکن جہاں جہاں اور جوں جوں انسان کی بعض صلاحیتیں بڑھتی چلی گئیں ، بیماریاں بڑھتی
چلی گئیں.دل کی بیماریاں بھی ان میں سے ایک ہیں.اس کا علاج کا طریقہ آ پریشن کے ذریعہ
سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو سمجھایا.پھر اس میں ترقی ہوئی تو ایک اور طریقہ اینجو پلاسٹی کا سمجھایا
جو اس سے زیادہ آسان ہے.اور اب مزید سٹیم سیل (Stem Cell) کے ذریعے علاج کی
ریسرچ ہو رہی ہے.بہر حال اللہ تعالیٰ انسانی صلاحیتوں کو ساتھ ساتھ اس کی ضروریات کے
مطابق اجا گر کرتا چلا جاتا ہے.اور یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہے.یہ وہ اعلیٰ رب ہے جس کی
تعریف ایک بندے پر فرض ہے.وہ اگر عیبوں کو ظاہر فرماتا ہے تو اس کے لئے پھر اس کا
مداوا اور علاج بھی سمجھا دیتا ہے.ایک موحد جب بھی نئی ریسرچ دیکھتا ہے تو اسے خدا تعالیٰ
کے فضل کی طرف منسوب کرتا ہے.اور جب اللہ تعالیٰ جسمانی بیماریوں کے علاج کی طرف
یوں رہنمائی فرما رہا ہے تو روحانی بیماریوں کے علاج کے سامان بھی کرتا ہے اور کیوں نہیں
کرے گا.پس ہر زمانے میں انبیاء روحانی بیماریوں کے علاج کے لئے آئے اور اپنے اپنے
وقت کی بیماریوں کے علاج کرتے رہے.جب انسانی زندگی روحانی بیماریوں کا مجموعہ بن گئی
اور نئی نئی بیماریاں پیدا ہوگئیں، ہر زمانے کی بیماری جمع ہو گئی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو
مبعوث فرمایا اور قرآن کریم کی کامل تعلیم اتاری جس نے علاج کیا اور آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں اس کے اعلیٰ ترین نمونے اپنی قوتِ قدسیہ سے دکھائے.اس
تعلیم کی روشنی میں دکھاتے جس سے انسانوں کو ، جانوروں کو باخدا انسان بنا دیا.لیکن ایک
زمانے کے بعد جب مسلمان بھی اس تعلیم کو سمجھنے سے قاصر ہو گئے اور اس پر عمل کرنا بھول گئے
690
Page 699
تو اللہ تعالیٰ نے مسیح موعود کو اپنے وعدے کے مطابق بھیجا جنہوں نے پھر اس تعلیم میں سے جو
قرآن کریم کی صورت میں موجود تھی، علم و عرفان کے موتی نکال کر ہماری بیماریوں کے علاج
کئے.اور یہ بتایا کہ امت میں جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، ان کے علاج یہ ہیں.اور میرے ساتھ
جڑو گے تو اس سے اپنے علاجوں میں کامیاب ہو سکتے ہو.ڈاکٹروں کو تو نئی بیماریوں کا علاج
ایک ریسرچ اور لمبا عرصہ محنت کرنے سے پتہ لگتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے روحانی علاج کے لئے
چودہ سو سال پہلے قرآن کریم میں کامل شریعت اتار کر یہ علاج رکھ دیا تھا.اور ہر زمانے میں جو
اللہ کے بندے تھے اس کو سمجھتے رہے.اور آخر پر جو مزید نئی بیماریاں پیدا ہوئی تھیں ان کے
علاج حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے آکر اسی جگہ سے بتا دئیے.کیونکہ قرآنِ کریم
کا فہم اور عرفان اس زمانے کی بیماریوں کے مطابق آپ کو ہی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا.اور
پھر جب ہر قسم کی ناسخ و منسوخ کے الزام سے اس کلام قرآن کریم کو پاک کر دیا تو پھر ہی پتہ
لگ سکتا تھا کہ کیا صحیح علاج ہیں اور یہ کام بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی
فرمایا.اور حقیقی مومنوں اور قرآن کریم پر غور کرنے والوں کو آپ کی تفسیروں اور وضاحتوں اور
تعلیم کی روشنی میں جو قرآن کریم سے نکال کر آپ نے ہمارے سامنے رکھی حسب ضرورت یہ
علاج میسر آتے رہے.پس جو لوگ سمجھتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے
آنے کی ضرورت نہیں تھی یا اب کسی مصلح کے آنے کی ضرورت نہیں ہے.ان کی بیماریاں جو
ہیں وہ ظاہر ہو کر پھر بڑھتی چلی جاتی ہیں اور بڑھتی چلی جارہی ہیں لیکن وہ اس بات کو تسلیم کرنے
کو تیار نہیں کہ جو اس زمانے کا امام اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اس کو قبول کریں.یہ سب دشمنیاں
جو ہیں ان میں اضافہ ہوتا چلا جارہا ہے.خود کش حملے جو ہیں ،قتل وغارت جو ہے، دہشت گردی
جو ہے کیا یہ اسلامی تعلیم ہے؟ خدا کے نام پر اور مذہب کے نام پر ظلم جو ہے، یہ اسلام کی تعلیم
ہے؟ یقینا نہیں.صرف ان لوگوں نے نا سمجھی یاڈھٹائی کی وجہ سے اس تعلیم کو ماننے سے انکار
کر دیا ہے جو حقیقی تعلیم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پیش فرما رہے ہیں.یہ سب
چیزیں جو ہیں جس پر آج کل مسلمانوں کے عمل ہو رہے ہیں، یہ تو اپنے عارضی ربوں کو خوش
691
Page 700
کرنے کے لئے ہیں.جبکہ مسیح موعود واحد و یگانہ خدا کی طرف بلا رہے ہیں اور اس تعلیم پر عمل
کروانے کے لئے دعوت دے رہے ہیں جو اللہ تعالی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری
اور جو حقیقی اسلامی تعلیم ہے.ایک طرف تو بعض طبقوں کی طرف سے پریشان ہو کر یہ دعوے بھی
کئے جا رہے ہیں کہ کسی مصلح کی ضرورت ہے.مسلمانوں میں خلافت کی ضرورت ہے.اور
دوسری طرف اس چیز کو ٹھیک کرنے کے لئے جب اللہ تعالیٰ نے اپنے سامان پیدا فرمائے
ہیں اور معالج بھیجا ہے تو اس کو قبول کرنے کے لئے یہ لوگ تیار نہیں ہیں.رض
پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے.وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدى (الاعلیٰ 4).جس نے طاقتوں کا اندازہ
کیا اور ہدایت دی.اس کا تعلق بھی پہلی آیت سے ہے.اس کے بارے میں حضرت
مصلح موعود نے فرمایا کہ قدَّدَ فَهَدی کے دو معنی ہوں گے.جیسا کہ پچھلی آیت میں بتایا گیا
ہے کہ چونکہ انسان میں ترقی کی استعداد رکھی گئی تھی اور اسے کامل القویٰ بنایا گیا تھا اس لئے
خدا تعالیٰ نے اس کی طاقتوں کا اندازہ کر کے اس کے متواتر ترقی کرتے چلے جانے کے ذرائع
مہیا کئے ہیں.یعنی پہلے پیدائش کو اس تعلیم اور طاقت کے مطابق کیا پھر تعلیم بھجوائی.یعنی جوں
جوں ذہنی اور جسمانی طاقتوں نے ترقی کی اللہ تعالیٰ نے اس کے مطابق ہدایت کے سامان
پیدا فرمائے.اور دوسرے معنے یہ ہیں کہ جب بھی انسان بج ہوا اللہ تعالی نے اس کی ضرورت
کے مطابق ہدایت بھیجوا دی.(ماخوذ از تفسیر کبیر جلد 8 صفحہ 405-406 مطبوعد ربوہ ) اور جیسا کہ پہلے ذکر
ہو چکا ہے کہ یہ ہدایت کامل طور پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ نازل فرمائی تا کہ
انسان اللہ تعالیٰ کے حقوق کا بھی صحیح ادراک کر سکے اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے اور بندوں کے
حقوق بھی ادا کرے.پس جب یہ ہدایت آگئی تو اس کے مطابق ہی اب ایک مومن کو چلنا
ہے.اور اگر سمجھ نہیں آتی تو پھر جو امام اور جو معالج اللہ تعالی نے بھیجا ہے اس کی طرف رجوع
کرنا ہوگا.اسی میں دنیا کی بقا ہے.جس کے لئے پہلی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے طریق بیان
فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور اس کی عبادت کی ضرورت ہے اور اس بھیجے ہوئے کو ماننے کی
ضرورت ہے.اگر سمجھ نہیں آتی تو پھر اللہ تعالیٰ سے خالص ہو کر مدد مانگی جائے کہ اللہ تعالیٰ صحیح
692
Page 701
راہنمائی فرمائے تا کہ ہم اس کا حق ادا کر سکیں.اور دوسرے اس تسبیح کے ساتھ اللہ تعالیٰ
کے پیغام کو دنیا تک پہنچانا بھی فرض ہے.اور یہی ہر قسم کی کجی سے پاک ایک مومن کی
نشانی ہے.اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم خالص ہو کر اس کے بھیجے ہوئے کے ساتھ جڑ کر اس
تعلیم کے مطابق عمل کرنے والے ہوں اور صحیح رنگ میں تسبیح کرنے والے ہوں، اس کی
عبادت کرنے والے ہوں اور اس کے پیغام کو پہنچانے والے ہوں.“
خطبہ جمعہ حضرت خلیفة المسیح الخامس اید و الله فرمودہ 14 مئی 2010ء)
693
Page 703
XXXXXXX
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
هَلْ أَتَكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ن
وَجُوْهٌ يَوْمَيذٍ خَاشِعَةٌ )
عَامِلَةً نَّاصِبَةٌ )
تَصْلَى نَارًا حَامِيَةً
سورة الغاشيه
1 - (میں) اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا
( اور ) بار بار رحم کرنے والا ہے ( پڑھتا ہوں )
2.کیا تجھے (دنیا پر ) چھا جانے والی (مصیبت) کی بھی
خبر پہنچی ہے؟
3.اس دن ( جب وہ مصیبت چھا جائے گی ) کچھ
چہرے اترے ہوئے ہوں گے.4.(وہ) محنت کر رہے ہوں گے ( اور ) تھک کر نچور ہو
رہے ہوں گے.5- ( لیکن اس محنت سے کوئی فائدہ نہ ہوگا اور ) وہ
جماعت ( بہر حال ) ایک بھڑکتی ہوئی آگ میں
داخل ہوگی.تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ أَنِيَةٍ ن
6 اور اس ساری جماعت کو اُبلتے ہوئے
چشمہ سے ( پانی ) پلایا جائے گا.لَيْسَ لَهُمْ طَعَامُ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ 7.اس کو سوکھے شبرق گھاس کے سوا اور کوئی کھانا
لَّا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِى مِنْ جُوعٍ
نہیں ملے گا.8.جو نہ تو انہیں موٹا کرے گا اور نہ بھوک ( کی تکلیف)
سے بچائے گا.وُجُوْهُ يَوْمَبِذٍ نَّاعِمَةٌ }
نِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ 3
فِي جَنَّةٍ عَالِيَة
لَّا تَسْمَعُ فِيهَا لَا غِيَةً
9.کچھ ( اور ) چہرے اس دن خوش بخوش ہوں گے.10.اپنی ( سابقہ ) کوششوں پر مطمئن ہوں گے.11 - بلند و بالا ) جنت میں ( رہ رہے ) ہوں گے.12.وہ اس میں کوئی لغو بات نہ سنیں گے.695
Page 704
فِيْهَا عَيْنُ جَارِيَةً
فِيهَا سُرُرٌ مَّرْفُوعَةٌ
13.اس میں ایک بہتا ہوا چشمہ ہوگا.14.( اور ) اس (جنت) میں اونچے تخت ( بھی ) رکھے
ہوں گے.وَاكْوَابٌ مَّوْضُوعَةٌ
15.اور آب خورے دھرے ہوئے ہوں گے.وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ
16.اور سہارا لینے والے چھوٹے سائز کے تکیے
قطاروں میں ( ٹیک لگانے کے لئے) رکھے ہوں گے.وَزَرَانُ مَبْثُوثَةٌ
أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ
كَيْفَ خُلِقَتْ قُ
وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ
وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ
وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ
17.اور قالینیں بچھی ہوئی ہوں گی.18.کیا وہ بادلوں کو نہیں دیکھتے کہ وہ کس طرح پیدا
کیے گئے ہیں.19.اور آسمان کو ( نہیں دیکھتے کہ ) کس
طرح اونچا کیا گیا ہے.20.اور پہاڑوں کو (نہیں دیکھتے ) کہ کس
طرح گاڑے ہوئے ہیں.21.اور زمین کو ( نہیں دیکھتے ) کہ کس طرح ہموار کی
ہوتی ہے.فَذَكِّرُ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكَّرَة
لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَّيْطِرٍ
إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَةٌ
فَيُعَذِّبُهُ اللهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَةُ
اِنَّ إِلَيْنَا ثِيَابَهُمْ)
ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْن
22.پس نصیحت کر کہ تو تو صرف نصیحت کرنے والا ہے.23 - توان (لوگوں) پر داروغہ (کے طور پر ) مقرر
نہیں ہے.24.مگر جس نے پیٹھ پھیر لی اور کفر کا مرتکب ہوا.25.اس کے نتیجہ میں اللہ اسے سب سے بڑا
عذاب دے گا.-26.یقیناً انہیں ہماری ہی طرف کو ٹنا ہے.27.پھر ان سے حساب لینا بھی یقیناً ہمارا ہی کام ہے.696
Page 705
أفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِيلِ كَيْفَ خُلِقَتْ
حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں:
قرآن شریف میں جو یہ آیت آئی ہے اَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ.آیت نبوت اور امامت کے مسئلہ کو حل کرنے کے واسطے بڑی معاون ہے.اونٹ کے عربی
زبان میں ہزار کے قریب نام ہیں اور پھر ان ناموں میں سے اہل کے لفظ کو جو لیا گیا ہے اس
میں کیا سر ہے؟ کیوں الى الجبل بھی تو ہو سکتا تھا؟
اصل بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جمل ایک اونٹ کو کہتے اور اہل اسم جمع ہے.یہاں
اللہ تعالی کو چونکہ تمدنی اور اجماعی حالت کا دکھانا مقصود تھا اور جمل میں جو ایک اونٹ پر بولا جاتا
ہے یہ فائدہ حاصل نہ ہوتا تھا اس لئے ابل کے لفظ کو پسند فرمایا.اونٹوں میں ایک دوسرے کی
پیروی اور اطاعت کی قوت رکھی ہے.دیکھو اونٹوں کی ایک لمبی قطار ہوتی ہے اور وہ کس طرح پر
اس اونٹ کے پیچھے ایک خاص انداز اور رفتار سے چلتے ہیں اور وہ اونٹ جوسب سے پہلے بطور
امام اور پیش رو کے ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو بڑا تجربہ کار اور راستہ سے واقف ہو.پھر سب اونٹ
ایک دوسرے کے پیچھے برابر رفتار سے چلتے ہیں اور ان میں سے کسی کے دل میں برابر چلنے کی
ہوس پیدا نہیں ہوتی جو دوسرے جانوروں میں ہے جیسے گھوڑے وغیرہ میں.گو یا اونٹ کی سرشت
میں اتباع امام کا مسئلہ ایک مانا ہوا مسئلہ ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ
کہہ کر اس مجموعی حالت کی طرف اشارہ کیا ہے جبکہ اونٹ ایک قطار میں جا رہے ہوں اسی طرح
پر ضروری ہے کہ تمدنی اور اتحادی حالت کو قائم رکھنے کے واسطے ایک امام ہو.پھر یہ بھی یادر ہے کہ یہ قطار سفر کے وقت ہوتی ہے.پس دنیا کے سفر کو قطع کرنے کے
واسطے جب تک ایک امام نہ ہو انسان بھٹک بھٹک کر ہلاک ہو جاوے.697
Page 706
پھر اونٹ زیادہ بارکش اور زیادہ چلنے والا ہے اس سے صبر و برداشت کا سبق ملتا ہے.پھر اونٹ کا خاصہ ہے کہ وہ لمبے سفروں میں کئی کئی دنوں کا پانی جمع رکھتا ہے.غافل نہیں
ہوتا.پس مومن کو بھی ہر وقت اپنے سفر کے لئے طیار اور محتاط رہنا چاہیے اور بہترین زادِ راہ
تقویٰ ہے.فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى
أَفَلَا يَنظُرُون کے لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دیکھنا بچوں کی طرح دیکھنا نہیں ہے بلکہ اس
سے اشباع کا سبق ملتا ہے کہ جس طرح پر اونٹ میں تمدنی اور اتحادی حالت کو دکھایا گیا ہے
اور ان میں اشباع امام کی قوت ہے اسی طرح پر انسان کے لئے ضروری ہے کہ وہ اشباع امام
اپنا شعار بناوے کیونکہ اونٹ جو اس کے خادم ہیں ان میں بھی یہ مادہ موجود ہے.كَيْفَ خُلقت میں ان فوائد جامع کی طرف اشارہ ہے جو اہل کی مجموعی حالت سے پہنچتے ہیں.احکم جلد 4 نمبر 42 مورخہ 24 نومبر 1900ءصفحہ5،4)
هَلْ أَنكَ حَدِيثُ الْعَاشِيَةِ.حضرت خلیفہ اسیح الاوّل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:
ا حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ.اکثر اہل تفاسیر نے قیامت کے حوادث مراد لئے ہیں.یہ صحیح بات
ہے کہ قیامت کے حوادث اپنے ہولناک ہونے کی وجہ سے غاشیات ہی ہوں گے کہ انسانوں
کے ہوش و حواس عقل و فکر سب کچھ مارے جائیں گے مگر قرآن کریم کے اسلوب اور اس کے
لٹریچر پر نظر کرنے سے پتہ لگتا ہے کہ جہاں کہیں قرآن شریف میں هَلْ أَتَكَ حَدِيثُ كَذَا وَ
گذا آیا ہے وہاں دنیوی عقوبات ، اخروی عقوبات کے ساتھ پیوستہ بلکہ مقدم رکھے گئے ہیں
جیسا کہ هَلْ آتك حَدِيثُ الْجُنُودِ فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ (بروج 19-18) هَلْ أَتَكَ حَدِيثُ مُوسى
وغیرہ آیات سے ثابت ہے.اسی طرح سے جیسا کہ انبیاء سابقین اور ان کی امم کے ساتھ جو
معاملات ہوئے ان کے ہم رنگ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی کوئی عظیم اله
عقوبت آسمانی آنے والی تھی اس کو هَلْ أَنكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ میں ذکر فرمایا.عقوبتیں تو
698
Page 707
کفار پر بہت سی آئیں.مگر الفاظ قرآنی کا تتبع کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ حدیث الغاشیہ
قحط شدید تھا جو سات سال تک بزمانہ نبوی واقع ہوا تھا.ایک روایت میں آیا ہے کہ آپ
نے اللهُمَّ أَعِلَى عَلَيْهِمْ بِسَبْع كَسَبْعِ يُوسُفَ کے الفاظ سے دُعا کی تھی.اس دعا کا اثر یہ ہوا
کہ وہ قحط شدید پڑا جس کا ذکر سورۃ دخان میں ان الفاظ سے ہے.يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ
مُّبِينٍ يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ اَلِيْمُ (الدخان -12-11) اس سورۃ شریف کی پہلی
آیت میں حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ہے اور سورۃ الدخان میں يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ
(ضمیمه اخبار بدر قادیان یکم اگست 1912ء)
وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ
جب قحط شدید ہوتا ہے تو فاقوں کی وجہ سے چہرے بگڑ جاتے ہیں.ذلت اور مسکنت
چہروں پر جم جاتی ہے.عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ لوگ یوں ہو جاتے ہیں کہ کھیتیوں زراعتوں کے پیچھے
محنت کرتے تھک کر کچور ہو جاتے ہیں مگر پیداوار کچھ نہیں ہوتی.محنت کرنا اور تھکنا یہی پلے
پڑتا ہے.(ضمیمه اخبار بدر قادیان یکم اگست 1912ء)
تضلی نَارًا حَامِيَةٌ تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ.عَذَابُ الجوع کی آگ سے شکم تنور ہوجاتا ہے.سرد پانی کہاں جو پینے کو ملے کہیں
دور دراز جگہ سے یا عمیق در عمیق چاہ سے لایا جاوے گا.انيّة لفظ آئی بمعنی تاخیر سے مشتق ہے.دوسری جگہ فرمایا - يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ أن (الرحمن 45) پہاڑوں میں جہاں سے
چشمے نکلتے بعض چشموں کا پانی نہایت سخت گرم ہوتا ہے.پیاسے کے لئے جس کی جان جاتی ہو
یہی گرم پانی غنیمت سمجھا جاتا ہے.لَيْسَ لَهُمْ طَعَامُ إِلَّا مِنْ طَرِيع.(ضمیمه اخبار بدر قادیان یکم اگست 1912ء)
ضریع ایک قسم کی گھاس ہے.جب تک پانی کی وجہ سے ہری رہتی ہے شہرق کہلاتی
699
Page 708
ہے مگر جب سوکھ جاتی ہے تو اسی کو ضریع کہتے ہیں.کانٹے دار اور بدبودار تلخ ہوتی ہے.تضرع
اسی سے مشتق ہے.سورۃ المومنون رکوع چہارم پارہ نمبر 18 میں فرمایا ہے کہ قحط شدید میں ضریع
کو کھا کر بھی تضرر ع نہیں کیا.كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى :
وَلَقَد أَخَذُ لَهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ (المومنون (77) اس
آیت شریف کا نزول مفسرین نے قحط شدید کے وقوع کے بارے ہی میں لکھا.پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت میں ہوا تھا.وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ
ہے جو
(ضمیمه اخبار بدر قادیان یکم اگست 1912ء)
جن لوگوں کے شامل حال خداوند کریم کا فضل ہوتا ہے.ان کے لئے ضرر کے سامان
بھی ضرررساں نہیں ہوتے.ہمارے ملک میں بڑے بڑے شدید قحط پڑے مگر جو فاتح قو میں
تھیں.قحط میں بھی وہ متنعم ہی رہیں.ع
منعم بکوه و دشت و بیابان غریب نیست هر جا که رفت خیمه زد و بارگاه ساخت
و
یہ ظاہر امر ہے کہ مکہ میں یہ آیات آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہورہی ہیں.اور
اسی حالت میں اہلِ مکہ کو بتایا جاتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو آج تم ایک
بے کس اور بے بس یقین کرتے ہو اور فی الواقعہ آج بھی وہ ایسا ہی ہے بھی.کیونکہ کوئی جٹھہ
اور جمیعت اس کے ساتھ نہیں اور تم سمجھتے ہو کہ بہت جلد اسے نابود کر دو گے.مگر یا درکھو کہ ایک
وقت آتا ہے کہ اس کی قوت اور شوکت کا دائرہ وسیع ہوگا اور تم سب اس کے زیر اقتدار ہو گے.اس وقت مخالفین عجیب گھبراہٹ کی حالت میں ہوں گے اور وہ ذلیل ہوں گے.ایک آگ
میں وہ داخل کئے جائیں گے.آگ سے مراد نار الحرب بھی ہوتی ہے.اور جہنم بھی.پس دنیا
کی جنگ میں ان کی ناکامی اور نامرادی نار جہنم کے لئے دلیل ہے.وہ اس مقابلہ میں ہار
جائیں گے.ان کو کھولتا ہوا پانی اور خاردار جھاڑیاں جن کو چھتر تھوہر کہتے ہیں کھانے کو ملیں
گی.اس کا ثبوت دنیا میں یوں ملتا ہے کہ آتشک کے مریض کے لئے تھوہر کے دودھ میں
700
Page 709
گولیاں بنا کر دی جاتی ہیں اوپر سے گرم گرم پانی پلایا جاتا ہے.غرض دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے.اسی طرح پر آخرت میں بھی ہوگا.رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ (الفرقان 66) - آمین.ان کے بالمقابل ایک گروہ خوش و خرم ہوگا اور اپنی تدابیر کے پورے ہونے اور مساعی
میں خدا کے فضل سے کامیاب ہونے پر شاداں و فرحاں ہوگا.ان کے لئے باغات عالی مرتبہ
ہوں گے جن میں لغویات کو دخل نہیں.اس میں بہتے ہوئے چشمے ہوں گے اور تخت ہوں گے.کوزے آبخورے قرینہ سے رکھے ہوں گے.قالین اور تکیے لگے اور بچھے ہوئے.غرض یہ تمام
انعامات اس دنیا میں صحابہ کو ملے اور انہوں نے ایسے باغات حاصل کئے.ان تمام امور پر
پہلے مختلف جگہ ہم نے بحث کر دی ہے.اب زیادہ تفصیل اور توضیح کی ضرورت نہیں.المختصر
مکہ معظمہ میں منکرین کو عذاب کی اور موافقین و متبعین کو کامیابی اور جنات عالیہ کی خوشخبری
برنگ پیشگوئی دی جاتی ہے.اور بتایا ہے کہ قیامت میں بھی ایسا ہی ہوگا.دنیا میں اس طرح پر
ہوا.اور یہ قیامت کا ثبوت ٹھہرا.(ضمیمه اخبار بدر قادیان یکم اگست 1912ء)
أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ
اس آیت شریف اور اس کے مابعد کی اور تین آیتوں میں صبر اور استقلال اور
مصائب کے وقت یک رنگی کا بیان ہے.سب سے پہلے اونٹ کا ذکر فرمایا کہ کس طرح وہ
بارکش اور نافع للناس وجود ہے.وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ
نزول بلا کے وقت اہلِ صفا آسمان کی طرح مرفوع الاحوال پہاڑوں کی طرح
مستقل المزاج اور زمین کی کشادگی کی طرح وسیع الحوصلہ ہوتے ہیں.بعض کوتاہ نظر معترضوں نے
ابل سماء جبال اور ارض ان چار مناظر کو ایک جگہ مذکور دیکھ کر اعتراض کیا ہے کہ کلام بے ربط
ہے.کوئی بات آسمان کی ہے تو کوئی زمین کی.ایک جانور ہے تو دوسرا پہاڑ.یہ اعتراض قلت تدبر
اور سور نہم کی وجہ سے ہے.ورنہ مناسبت ایسی تام اور ابلغ ہے کہ نظارہ قدرت میں اس سے بڑھ کر
701
Page 710
جامع الصفات چیزیں دوسری ہیں نہیں جو فہمائش کے لئے پیش کی جائیں.لَسْتَ عَلَيْهِمْ مُصَيْطِرٍ
(ضمیمه اخبار بدر قادیان یکم اگست 1912ء)
مُصَيْ رس اور ص دونوں سے لکھا جاتا ہے.اس کے معنے جابر کے ہیں.نبی کا کام
صرف
تبلیغ کر دینا ہے.جو نہ مانے ان پر نبی جبر نہیں کیا کرتے.فَيُعَذِّبُهُ اللهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ.(ضمیمه اخبار بدر قادیان یکم اگست 1912ء)
اس آیت شریفہ سے معلوم ہوتا ہے کہ قحط کے عذاب کے علاوہ کوئی اور بھی عذاب
ہے جس کا نام عذاب اکبر رکھا ہے.دوسری جگہ فرمایا.وَلَنُذِيُقَنَّهُمْ مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْلى
دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ (السجد 228) سورۃ دخان اور سورۃ المومنون میں پیغمبر صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم کے وقت قحط کی آیتوں سے سورۃ الغاشیہ کے الفاظ ملتے جلتے ہیں.اس لئے حَدِيث
الْغَاشِيَة سے قحط شدید کی پیشگوئی ہم نے مراد لی ہے.اور بھی سورۃ الغاشیہ میں ایسے الفاظ لائے
گئے ہیں.جیسے ضَرِيع لا يُسْمِنُ عَامِلَة نَاصِبَة وغیرہ قحط ہی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں.حدیث الغاشیہ سے بطور معارف کوئی اور بھی قسم عذاب کی مراد ہو تو ممکن ہے.کیونکہ
کلام الہی ذو المعارف ہوتا ہے.تا وقتیکہ تضاد نہ ہو سارے ہی معارف صحیح سمجھے جا سکتے ہیں.پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورۃ الاعلی اور سورۃ الغاشیہ کو اکثر نماز جمعہ اور عیدین میں ان
سورتوں کے ذوالمعارف ہونے کی وجہ سے تلاوت فرماتے تھے.نماز عشاء میں بھی ان دو
سورتوں کا کثرت سے پڑھنا آپ کا ثابت ہے.ماخوذ از حقائق الفرقان زیر سورۃ الغاشیہ )
حضرت خلیفہ المسیح الثانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:
(ضمیمه اخبار بدر قادیان یکم اگست 1912ء)
اس سورۃ کا نام غاشیہ ہے اور یہ سورۃ بغیر کسی اختلاف کے ملی ہے.702
Page 711
مسند احمد بن حنبل اور مسلم اور سنن نسائی اور سنن ابوداؤد اور ابن ماجہ میں نعمان بن بشیر
روایت آتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ اور عیدین کی پہلی رکعت میں سبح اسم
ريك الأغلى اور دوسری میں سورۃ الغاشیہ پڑھا کرتے تھے بلکہ اگر دونوں نمازیں جمع ہو جاتی
تھیں یعنی کبھی عید الفطر اور جمعہ اکٹھے ہو جاتے یا عید الضحی اور جمعہ اکٹھے ہو جاتے تب بھی آپ
دونوں نمازوں میں یہ دونوں سورتیں پڑھا کرتے تھے.اس سورۃ اور سورۃ الاعلیٰ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جمعہ اور عیدین میں پڑھنا اور
بالالتزام پڑھنا اور اتنا تعہد کرنا کہ اگر دونوں نمازیں جمع ہو جائیں تب بھی آپ دونوں میں
التزاما یہ سورتیں پڑھا کرتے تھے بتاتا ہے کہ اسلام کی اجتماعی زندگی کے ساتھ یہ دونوں سورتیں
گہرا تعلق رکھتی ہیں.سورۃ الاعلیٰ کا جوڑ تو نظر ہی آتا ہے کہ اس میں قرآن کریم کے قول فصل
ہونے کے لحاظ سے بحث کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ کس طرح اسلام اپنے انتہائی کمال کو
پہنچ جائے گا.اس ضمن میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اسلام کو ایسے خادم مل جائیں گے جو قرآن کریم
کے حافظ ہوں گے.اسی طرح اس کی حفاظت کے متعلق اور کئی قسم کی غیر معمولی تحریکات دنیا
میں جاری ہوجائیں گی.گویا سورۃ الاعلی اسلامی ترقی اور دین اسلام کی اشاعت، اُس کے ماننے والوں کی زیادتی
اور مسلمانوں کے غلبہ پر دلالت کرتی تھی.اور سورۃ الغاشیہ میں گو وہ مضمون نہیں مگر اس میں بھی یہ
بات ضرور پائی جاتی ہے کہ کافروں کے اسلام کے خلاف اُٹھنے اور زور لگانے کا اس میں اشارہ
کیا گیا ہے اور مومنوں کا ان کے مقابلہ میں کامیاب ہونا اشارۃ بیان کیا گیا ہے.مگر چونکہ ابھی
اسلام کے ابتدائی ایام تھے اور خواہ مخواہ کفار کو بھڑکانا مقصود نہیں تھا اس لئے جنگ اور مقابلے کا
اللہ تعالیٰ صریح الفاظ میں ذکر نہیں کرتا بلکہ ایسے الفاظ میں ذکر کرتا ہے جو ٹھیس لگانے والے نہ
ہوں.جس طرح دشمن نے کھلے طور پر مخالفت کا اظہار نہیں کیا تھا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی
کھلے طور پر یہ ذکر نہیں کیا کہ مسلمان لڑیں گے اور کفار کو مغلوب کریں گے صرف نتیجہ کا ذکر کر
703
Page 712
دیا ہے کہ اسلام کے خلاف مخالفین کچھ کوششیں کریں گے لیکن وہ اسلام کو گزند پہنچانے میں
ناکام رہیں گے اور آخر مسلمانوں کو اپنے مخالفین پر غلبہ حاصل ہو جائے گا.گویا صاف الفاظ میں
اس سورۃ میں لڑائی کا ذکر نہیں کیا ، صرف اشارہ اس کا ذکر کیا ہے تا کہ اس وقت جب کہ مخالفین
اسلام نے کھلے طور پر حملہ نہیں کیا تھا اس قسم کی باتوں کی وجہ سے اسلام کی طرف سے ابتدا نہ
سمجھی جائے اور یہ خیال نہ کیا جائے کہ کفار کو انہوں نے بھڑکا دیا ہے.اس سورۃ کا مضمون بھی اجتماعی کاموں پر دلالت کرتا ہے.چنانچہ اس سورۃ میں ایک مجموعہ
افراد کا ذکر کرتے ہوئے پیشگوئی کی گئی ہے کہ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ.ان الفاظ
میں اللہ تعالیٰ نے صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترقی کی خبر نہیں دی بلکہ جماعت مسلمہ کی
ترقی کی بھی خبر دی ہے.اسی طرح وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ میں اجتماعی طور پر کفار کے متعلق خبر دی گئی
ہے کہ وہ مسلمانوں کے مقابلہ میں ناکام رہیں گے.حقیقت یہ ہے کہ جس طرح سورۃ الاعلیٰ
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اور آخری زمانہ یعنی ہر دو زمانوں کے متعلق ہے اور یہ سورۃ
بھی ان دونوں زمانوں کے حالات بیان کرتی ہے.چونکہ ان دونوں سورتوں کا مضمون ایسا ہے جو شروع زمانہ اسلام سے آخر زمانہ اسلام تک
تعلق رکھنے والا تھا.اس لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جمعہ اور عیدین میں بالالتزام اِن
دونوں سورتوں کی تلاوت فرمایا کرتے تھے.جمعہ اور عیدین جو اجتماع کے مواقع ہیں اُن میں
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اِن دونوں سورتوں کا تلاوت کرنا بتاتا ہے کہ جب بھی مسلمان
اجتماعی طاقت پکڑنے کی طرف متوجہ ہوں گے اور جب بھی خدا تعالیٰ مسلمانوں کی کمزوری کو ڈور
کرنے لگے گا اُس وقت یہ دونوں سورتیں اپنے مطالب کے لحاظ سے ظاہر ہو جائیں گی.سورۃ الاعلیٰ میں یہ بات واضح کی گئی تھی کہ مسلمانوں کی ترقی اسی وقت ہو گی جب
قرآن کریم کے معارف اور اُس کے علوم کو ظاہر کرنے والا مامور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے
704
Page 713
گا.گویا مسلمانوں کی ترقی کبھی بھی دنیوی ذرائع سے نہیں ہوگی بلکہ مامورین پر ایمان لانے
اور ان کی ہدایات پر چلنے کے ذریعہ ہوگی جیسا کہ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَی کے الفاظ اس پر شاہد
ہیں کہ قرآن کریم کے خدام جو بھولے ہوئے قرآن کو پھر واپس لائیں گے اُن کے ذریعہ ہی
مسلمان اپنی کھوئی ہوئی عزت کو حاصل کر سکیں گے.آج جو مسلمان سیاسی ذرائع سے ترقی حاصل کرنا چاہتے ہیں اُن کو سورۃ الاعلیٰ کے
مضامین کی طرف توجہ کرنی چاہئے.اب اس سورۃ میں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جب بھی
اسلام کی ترقی ہوگی تلواروں کے سایہ کے نیچے ہوگی.کبھی کوئی مامور ایسا نہیں آسکتا جس کے
آنے پر دُنیا اُس کا خوشی سے استقبال کرے اور کہے جی آیاں نوں“ یا ”بھلے آئے“ یا
بر سر و چشم بلکہ جب بھی کوئی مامور آئے گاوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ کی حالت
رونما ہوگی اور ضرور اس کی مخالفت ہو گی.اس مخالفت کے بغیر کسی روحانی سلسلہ کی ترقی کا امکان
بالکل ناممکن ہے.اگر حضرت مسیح ناصری جیسا کہ مسلمان سمجھتے ہیں کسی وقت آسمان سے اتر
آئیں تو ان کے زمانہ میں وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ عَامِلَةٌ قاصِبَةٌ کی کوئی صورت نہیں ہوسکتی.لوگ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جائیں گے اور اُن کے حلقہ غلامی میں شامل ہو جائیں گے کیونکہ
فرشتے اُن کے ساتھ ہوں گے اور کسی کو انکار کی جرات نہیں ہو سکے گی.مگر الہی سنت کے
ماتحت ایسا کبھی نہیں ہو سکتا.ضروری ہے کہ ہر الہی سلسلہ کی مخالفت ہو اور مخالفت کے بعد اُس
کو ترقی نصیب ہو.غرض اِن دونوں سورتوں سے پتہ لگتا ہے کہ اسلام کو ہمیشہ شدید مخالفت کے
بعد ترقی ہوتی ہے.پس یہ دونوں سورتیں مضامین کے لحاظ سے آپس میں گہرا تعلق رکھتی ہیں.ان ہر دو سورتوں میں اسلام کی ترقی کے دو اصول بیان کئے گئے ہیں.سورۃ الاعلیٰ میں یہ
بتایا گیا ہے کہ جب بھی مسلمانوں کا تنزل ہوگا قرآن کریم کے بھولنے سے ہوگا اور جب بھی
مسلمانوں کی ترقی ہوگی ایسے شخص کے ذریعہ ہوگی جو قرآن کو آسمان سے واپس لائے گا.گویا
ایسے مامور تو آئیں گے جو بھولے ہوئے قرآن کو یاد کرائیں گے مگر ایسے مامور نہیں آسکتے جو
705
Page 714
نئی شریعت لائیں.اور سورۃ الغاشیہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ مسلمانوں کی ترقی دور اول میں ہو یا دور آخر
میں ہمیشہ ایسے ماموروں کے ذریعہ ہوگی جن کی شدید مخالفت ہوگی مگر بالآخر وہ جیت جائیں گے
جیسا کہ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةُ عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ میں بتایا ہے.پس مسلمانوں کو یاد رکھنا چاہئے
کہ اُن کی ترقی ہمیشہ مامورین پر ایمان لانے اور ساری دنیا سے لڑائی جھگڑا مول لینے کے بعد
ہوگی.ایسا وجود کوئی نہیں آسکتا جسے لوگ آپ ہی آپ مان لیں.پس آسمان سے کسی مامور
کے اترنے کا خیال بالکل خلاف قرآن ہے.هَل جب فعل سے پہلے آئے تو اس کے معنے قد کے ہوتے ہیں لیکن عام طور پر ھل
تصدیق ایجابی کے لئے ہوتا ہے.یعنی عام معنے اس کے ایسے سوال کے ہیں جس کے جواب
میں تصدیق کا مطالبہ ہوتا ہے سوائے اس کے کہ اس کے بعد الا آ جائے.اس وقت اُس کے
معنے نفی کے ہو جاتے ہیں.پس آیت کے معنے یا تو یہ ہوں گے کہ کیا حدیث غاشیہ آپہنچی یا
نہیں؟ یعنی آپہنچی ہے.اور یا پھر یہ معنی ہوں گے کہ وہ ضرور آپہنچی ہے.حدیث کے معنے خبر کے ہوتے ہیں (اقرب)
عاشِيَة : ماشینی کا مونث ہے اور اس کے معنے ہیں ڈھانکنے والی چیز.نیز عاشِيَةٌ
قیامت کا بھی نام ہے کیونکہ اس میں اس قدر ڈر اور خوف اور صدمہ کی باتیں ہوں گی کہ ان کی
وجہ سے وہ انسانی دماغ پر چھا جائے گی.(اقرب) جب کبھی کوئی بڑا حادثہ ہوتا ہے باقی
سارے حالات انسان کے دل سے محو ہو جاتے ہیں.قیامت چونکہ ایک بڑا بھاری حادثہ ہوگا
اور قرآن کریم سے پتہ لگتا ہے کہ اس وقت ہر شخص دوسرے کو بھول جائے گا یہاں تک کہ ماں
اپنے بچہ کو بھول جائے گی اور قیامت کا خیال باقی تمام خیالات پر مستولی اور غالب آجائے گا
اس لئے قیامت کو بھی غاشیة کہا جاتا ہے.اور غاشية جہنم کی آگ کو بھی کہتے ہیں
(اقرب) کیونکہ اس کا عذاب کامل ہے.عام عذاب ایسے ہوتے ہیں کہ اُن میں کوئی نہ کوئی
706
Page 715
پہلو عذاب سے بچا ہوا ہوتا ہے.ایک طرف سے اگر دُ کھ پہنچ رہا ہوتا ہے تو دوسری طرف سے
سکھ بھی پہنچ رہا ہوتا ہے...مگر جہنم کے عذاب کو غاشیہ اس لئے کہتے ہیں کہ وہ کامل عذاب ہوگا
اور اُس میں سکھ کا کوئی پہلو نہیں ہوگا.اور غاشية زبردست مصیبت کو بھی کہتے ہیں.چنانچہ
کہتے ہیں تأْتِيْهِ غَاشِيَةٌ مِنْ عَذَابِ اللهِ أَى نَائِبَةٌ تَغْشَاهُ.یعنی اُس پر ایسی مصیبت نازل ہو
گی جو اُس کو ڈھانپ لے گی (اقرب) اور غاشیة پیٹ کی بیماری کو بھی کہتے ہیں.اور
غاشية کے معنے ایسی جماعت کے بھی ہیں جو سوال کے رنگ میں یا کوئی اور فائدہ اُٹھانے
کے لئے انسان کے پیچھے پڑی رہے.(اقرب) سوالیوں کو اس لئے غاشیة کہتے ہیں کہ وہ
بُری طرح پیچھے پڑ جاتے ہیں.نوکروں چاکروں کو بھی غاشیة کہتے ہیں کیونکہ وہ بھی آقا کی
خوشنودی حاصل کرنے کے لئے اُس کے آگے پیچھے پھرتے ہیں.اسی طرح وہ دوست جو ایک
دوسرے سے ملنے کے لئے گھروں پر آتے جاتے ہیں وہ بھی غاشیۃ کہلاتے ہیں (اقرب)
قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ الہی عذابوں میں سے ایک عذاب خاص طور پر
غاشیہ کہلانے کا مستحق ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی آیا اور مسیح موعود
کے زمانہ کے لئے بھی اس کی پیشگوئی تھی.سورۃ دُخان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَارْتَقِبُ يَوْمَ
تأتي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ (الدخان 12-11) یعنی تُو
انتظار کر اُس دن کا جب آسمان پر دُھواں ہی دُھواں چھا جائے گا اور سارے انسانوں کو اپنے
اندر ڈھانپ لے گا.یہ عذاب ہے جو نہایت ہی درد ناک ہو گا.چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ
وسلم کو جب مکہ والوں نے سخت دُکھ دیا تو آپ نے اس پیشگوئی کے ماتحت دعا کی کہ اللهُمَّ
اعِتِى عَلَيْهِمْ بِسَبْعٍ كَسَبْعِ يُوسُفَ بخاری جلد 3 کتاب تفسیر القرآن) اے خدا ان
لوگوں نے مجھے سخت تنگ کر لیا ہے تو میری اُن سات سالوں سے مدد فرما جن سات سالوں سے
تو نے حضرت یوسف علیہ السلام کی مدد کی تھی.چنانچہ اس دعا کے نتیجہ میں اُس زمانہ میں شدید
قحط پڑا.بارشیں رُک گئیں اور اس قدر تباہی آئی کے مکہ والوں نے ابوسفیان کو خاص طور پر
707
Page 716
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا اور کہا کہ آپ کی قوم قحط کی وجہ سے برباد ہوگئی آپ دعا
کریں کہ اُن کی یہ حالت بدل جائے.(بخاری کتاب تفسير القرآن تفسير سورة
دخان) گویا جس طرح فرعون نے حضرت موسٹی کی طرف اپنے سفیر بھیجے تھے اسی طرح مکہ والوں
نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنا سفیر بھیجا اور درخواست کی کہ اس قحط کے دُور
ہونے کے متعلق دعا فرمائی جائے.چنانچہ آپ نے دعا کی اور اللہ نے اُس قحط کوڈ ور کر دیا.تو
غاشیہ سے مراد وہ عذاب دُخان بھی ہے جس کا ذکر سورۃ دُخان میں کیا گیا ہے.اس دخان مبین
کے عذاب کی مسیح موعود کے زمانہ کے لئے بھی پیشگوئی کی گئی ہے.چنانچہ حضرت مسیح موعود
علیہ السلام پر جو الہامات نازل ہوئے اُن میں ایک الہام یہ بھی ہے کہ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ
بِدُخَانٍ مُّبِيْنٍ وَتَرَى الْأَرْضَ يَوْمَئِذٍ خَامِدَةً مُّصْفَرَّةٌ ( تذکره صفحه 594)
غرض علاوہ اور عذابوں کے جن کی طرف حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسّلام کے
الہامات میں اشارہ کیا گیا ہے قحط کے عذاب کی خبر بھی آپ کے الہامات میں موجود ہے اور
بتایا گیا ہے کہ اس زمانہ میں لوگوں پر شدید تنگی اور مصیبت کے سال آئیں گے.چنانچہ
حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسّلام کے زمانہ میں علاوہ عام تحطوں کے جنگوں کی وجہ سے جو
قحط پڑے ہیں وہ ایسے شدید ہیں کہ اُن کی مثال پہلے زمانوں میں نہیں ملتی.هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ کے یہ معنے ہیں کہ کیا تمہیں معلوم ہے یا نہیں کہ غاشیہ
کہلانے والی مصیبت بھی آنے والی ہے.تھل چونکہ عام طور پر تصدیق ایجابی کے لئے آتا ہے
اس لئے اس کے معنے یہ ہوں گے کہ کیا حدیث غاشیہ آپہنچی کہ نہیں.یعنی آپہنچی ہے.لیکن
هل جب فعل سے پہلے آئے تو کبھی قد کے معنے بھی دیتا ہے.اس لحاظ سے آیت یوں ہوگی قد
آنكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ لواب مخالفتیں تیز ہونے والی ہیں اس لئے خدا تعالیٰ کی طرف سے
عذاب کی خبریں آرہی ہیں یا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تیری طرف حَدِيثُ الْغَاشِيَة بھیج
دی.دشمن اب شرارت میں بڑھنے والا ہے اس لئے ہم نے بھی عذاب کی خبریں دینی شروع کر
708
Page 717
دی ہیں.اور غاشیہ کے معنے چونکہ اس شخص کے بھی ہوتے ہیں جس کے پاس کثرت سے لوگ
آئیں اس لئے حَدِيثُ الْغَاشِيَة کے معنے فتوحات کے بھی ہو سکتے ہیں اور معنے یہ ہوں گے کہ
چاروں طرف سے لوگوں کے وفود تیرے پاس آئیں گے.گویا درمیانی زمانہ مخالفت کو چھوڑ دیا
اور آخری نتیجہ بیان کر دیا کہ تیرے پاس وفود آئیں گے.ان معنوں کے لحاظ سے حدیث
الْغَاشِيّة میں سالِ وفود کی خبر دی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ کفار سے جنگ ہوگی.تو اس جنگ
میں جیت جائے گا اور پھر چاروں طرف سے لوگوں کے وفود تیرے پاس آئیں گے.دشمن اُن کو
دیکھ دیکھ کر جل مرے گا اور مومن بہت بڑی ترقیات حاصل کریں گے.وجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ
وجود زوجہ کی جمع ہے اور وجہ کے اصل معنے تو چہرے کے ہوتے ہیں لیکن اس
کے علاوہ بھی اس کے کئی معنے ہوتے ہیں.چنانچہ ایک معنے سیّدُ الْقَوْمِ کے ہوتے ہیں یعنی
قوم کا سردار.پھر وجہ کے معنے اس انسان کے بھی ہوتے ہیں جو عزت اور وجاہت رکھتا ہو
(اقرب) چنانچہ کہتے ہیں رَجُلٌ وَجہ اور مراد ہوتی ہے ذُو جَاہِ یعنی فلاں آدمی بڑی عزت اور
وجاہت والا ہے پس وُجُونا کے معنے ہوئے کچھ لوگ جو معز سمجھے جاتے ہیں یا کچھ لوگ جو قوم
کے سردار ہیں.خَاشِعَةٌ خَشَعَ سے اسم فاعل مؤنث کا صیغہ ہے اور خَشَعَ لَهُ خُشُوعًا کے معنے
ہوتے ہیں ذلّ وَ تَطامَن.اُس سے دب گیا.اُس کے ماتحت ہو گیا.یا اُس کے سامنے جھکنا
پڑا.اور خَشَعَ بِبَصر ہ کے معنے ہوتے ہیں غصہ اس نے اپنی آنکھیں نیچی رکھیں.اور تقع
بصرة کے معنے ہوتے ہیں انگستر اُس کی نظر جھک گئی.یعنی ذلت اور رسوائی کی وجہ سے
انسان نے آنکھ اونچی نہ کی.اور خَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمٰنِ کے معنے ہیں سَكَنَتْ وَذَلَّتْ
وَخَضَعَت آوازیں دب گئیں اور خدا تعالیٰ کے سامنے ذلت اور اقرار اتباع پر مجبور ہو گئیں
(اقرب) پس وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ کے معنے ہوئے اُس دن کچھ سردارانِ قوم ہوں گے یا
709
Page 718
کچھ لوگ ہوں گے یا کچھ وجاہت والی ہستیاں ہوں گی جو بالکل ذلیل ہو جائیں گی اور اُن کی
آوازیں دب جائیں گی..ا نَاصِبَةٌ : نَصَب سے اسم فاعل مؤنث کا صیغہ ہے اور نَصَبَهُ الْهَم کے معنے ہوتے
میں اتعبہ تم نے اس کو تھکا دیا.اور نَصبُ فُلان الشیخ کے معنے ہوتے ہیں وَضَعَهُ وَضُعا
اور -
ثَابِنَّا كَنَصْبِ الرُّمح وَالْبِنَاء وَالْحَجَرِ یعنی کسی چیز کو مضبوطی سے گاڑ دیا جیسے نیزہ گاڑا جاتا ہے
یا بنیاد کو مضبوط بنایا جاتا ہے یا پتھر کو عمارت میں مضبوطی سے پیوست کر دیا جاتا ہے.وَرَفَعَهُ
ضلی نیز یہ لفظ اضداد میں سے ہے اور اس کے معنے بلند کرنے کے بھی ہوتے ہیں اور نصب
السیر کے معنے ہوتے ہیں رَفَعَهُ أَوْ هُوَ اَنْ نَّسِيرَ طُولَ يَوْمِهِ سَيْرًا لَيْئًا اُس نے سیر کو بلند کیا
یعنی خوب تیزی سے سفر کیا یا آہستہ آہستہ سارا دن سفر کرتا رہا.گویا اس کے دونوں معنے ہیں.یہ
بھی معنے ہیں کہ خوب گھوڑا دوڑا یا اور یہ بھی معنے ہیں کہ آہستہ آہستہ دیر تک سفر کرتا چلا گیا.اور
نَصَبَ بِغُلان کے معنے ہوتے ہیں عَادَاهُ اُس سے دشمنی کی اور نصب له الحزب کے معنے
ہوتے ہیں وَضَعَهَا اُس کے خلاف لڑائی کی اور نصب الْعَلَم کے معنے ہوتے ہیں رَفَعَهُ
وَأَقَامَهُ مُسْتَقْبلا به اس نے جھنڈے کو اپنے سامنے کھڑا کیا.اور نَصَبَ الشَّجَرَةً کے معنے
ہوتے ہیں غُرَسَهَا فِي الْأَرْضِ اُس نے زمین میں درخت گاڑا اور نَصَبَ السُّلْطَانُ فُلَانًا
کے معنے ہوتے ہیں ولا لا منصبا اس کو بادشاہ کے منصب پر مقرر کیا اور نصب الر بِفُلانٍ
کے معنے ہوتے ہیں اظهر له اس کے خلاف منصو بہ بازی کی اور نصبتَ لَهُ رَأْيَا کے معنے
ہوتے ہیں اشرت عَلَيْهِ بِرَأَي لا يَعْدِلُ عَنْهُ کہ تو نے ایسی رائے اُس کو دی جس سے
ادھر اُدھر نہ ہوسکا (اقرب)
وہ
پس عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ کے معنے ہوئے عمل کرنے والی جماعت یا اعلان جنگ کرنے والی یا
اپنی بنیادوں کو مضبوطی سے گاڑ دینے والی یا لمبے لمبے سفر کرنے والی یا اپنی دشمنیوں کا اظہار
کرنے والی یا عہدوں پر مقرر کرنے والی یا اپنے جھنڈوں کو اونچا کرنے والی یا نیزہ گاڑنے
710
Page 719
والی جماعت.(اقرب)
خاشعة کے معنے چونکہ عام مشکلات اور مصائب کے بھی ہیں جن میں وہ لڑائیاں بھی
شامل ہیں جو کفار سے ہوئیں.اس لحاظ سے عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ کے یہ معنے ہوں گے کہ اب مخالفین
اسلام تمہارے خلاف منصوبے کرنے والے ہیں اور اُن بغضوں اور کینوں کو جن کو وہ اپنے
دلوں میں چھپائے بیٹھے تھے ظاہر کرنے والے ہیں.سورۃ فاشیہ کا نزول رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت کے چوتھے سال کے
قریب ہوا ہے اور یہی وہ سال ہے جس میں کفار مکہ کی طرف سے منظم رنگ میں ایذا دہی کا
سلسلہ شروع ہوا.چنانچہ انہوں نے اپنے بغضوں اور شرارتوں کا اعلان کر دیا.پس اُن کے اس اعلان کی ہی
خبر خدا تعالیٰ نے وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ میں دی ہے کیونکہ نَاصِبَةٌ کے ایک
معنے افسر مقرر کرنے کے بھی ہوتے ہیں.اس لئے اس آیت میں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے
کہ وہ وقت آرہا ہے جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں مکہ والے کمانڈر اور افسر مقرر
کریں گے اور یہ لوگ پورا زور لگائیں گے کہ اسلام نہ پھیلے.چنانچہ پیشگوئی کے مطابق مخالفین
نے مخالفت کے جھنڈے گاڑ دئیے اور مقابلہ کے لئے اُتر آئے.پھر جن الفاظ میں مخالفین کی مخالفت خبر دی ہے وہ ایسے ہیں کہ ان سے مخالفت کی تفصیل اور
اُس کا انجام بھی معلوم ہو جاتا ہے.چنانچہ پہلے عاملہ کہا اور عاملہ میں انفرادی طور پر مکہ والوں
کے مخالفت کرنے کا ذکر تھا.مگر اس کے بعد تا صبة کا لفظ استعمال کیا اور ناصبة میں قومی طور پر
مخالفت کرنے کا ذکر ہے اور اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اب مکہ والے صرف انفرادی طور پر
نہیں بلکہ قومی طور پر اجتماعی رنگ میں بھی مخالفت کریں گے اور اپنے میں سے بعض کو افسر مقرر
کریں گے تا کہ ایک تنظیم کے ماتحت وہ مسلمانوں سے لڑیں اور اُن کو دق کریں.پھر تاصبة کے ایک معنے چونکہ تھکنے والی جماعت کے بھی ہیں.گویا آیت کے اس
711
Page 720
حصّہ میں مخالفت کے انجام کی طرف اشارہ کر دیا کہ اہالیانِ مکہ مخالفت میں پوری محنت صرف
کریں گے مگر اس کے نتیجہ میں اُن کو کوئی خوشی نہیں پہنچے گی.محنت کریں گے لیکن نتیجہ تھکان ہی
کان نکلے گا.آرام و راحت میٹر نہیں آئے گی.تَصْلى نَارًا حَامِيَةٌ
لا حامية : حمی سے ہے اور حَمِیتِ النَّارُ کے معنے ہوتے ہیں اشْتَدَّ حَرُهَا آگ
نہایت تیزی کے ساتھ بھڑک اٹھی (اقرب ) پس حَامِيَةٌ کے معنے ہوں گے شدت سے
بھڑ کنے والی.اور تضلی نَارًا حَامِيَةٌ کے معنے ہوں گے کہ مخالف جماعتیں بھڑکتی آگ میں
داخل ہوں گی.ساری آگیں ایک قسم کی نہیں ہوتیں.بعض آگیں زیادہ گرم ہوتی ہیں اور بعض
کم گرم.یہاں تک کہ بعض آگیں ایسی ہوتی ہیں کہ لوگ ننگے پاؤں صرف پاؤں
کو کیچڑ لگا کر
اُن کے اُوپر سے گزر جاتے ہیں اور انہیں کوئلوں کی گرمی محسوس نہیں ہوتی.مگر فرماتا ہے کہ وہ
آگ جس میں مخالفین داخل ہوں گے وہ تارا حَامِيَةً ہوگی.یعنی ایسی آگ جو اپنی تیزی اور
اپنی گرمی میں انتہا پر پہنچ چکی ہوگی.فرماتا ہے یہ مخالفت چاہے انفرادی ہو یا قومی ،مخالفین کی تباہی کا موجب ہوگی اور بجائے
اس کے کہ مخالف لوگ امن و آرام پائیں یا انہیں عزت اور کامیابی حاصل ہو یہ اس آگ میں
داخل ہوں گے جو سخت گرم ہوگی اور بھڑکنے میں تیز ہوگی.یعنی مسلمان ترقی کرجائیں گے اور
مخالفین اپنے منصوبوں میں ناکام و نا مرا در ہیں گے اور آگ میں جلیں گے.تشفى مِن عَيْنٍ آنِيَةٍ
عین کے عربی زبان میں بہت سے معنے ہیں.ان معنوں میں سے ایک چشمہ کے ہیں
اور دوسرے معنے بادل کے ہیں (اقرب ) اس آیت میں چونکہ تشفی کا لفظ استعمال ہوا ہے اس
لئے عین سے مراد چشمہ یا با دل ہی ہوسکتا ہے.دانية : أتى (يَأْني آنْيَا وَإِني وَآنَاءَ) سے ہے اور آئی کے معنے ہوتے ہیں دَی وَقَرُبَ
712
Page 721
وَحَضَر.وہ قریب ہو گیا اور سامنے آ گیا.جب پانی کے متعلق یہ لفظ بولا جاتا ہے تو اس کے معنے
ہوتے ہیں انقضی حده - کہ پانی سخت گرم ہو گیا ( اقرب) جیسے آگ کے متعلق کہتے ہیں
حَمِيتِ النَّارُ یعنی آگ سخت بھڑک اٹھی.اسی طرح پانی کے لئے جب یہ لفظ استعمال کیا
جائے تو اس کے معنے ہوتے ہیں وہ تیز گرم ہو گیا.پس تُسقى مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ کے یہ معنے ہوئے
کہ انہیں ایسے چشمے سے پانی پلایا جائے گا جو نہایت تیز گرم ہوگا یا ایسے بادلوں سے اُن پر پانی
برسے گا جونہایت شدید گرم ہوں گے اور ان کو جھلس کر رکھ دیں گے.انسان پانی پیتا ہے تو اس کی غرض یہ ہوتی ہے کہ پیاس بجھے اور پیاس ہمیشہ ٹھنڈا پانی
بجھاتا ہے.لیکن یہاں یہ ذکر ہے کہ ان کو سخت گھولتا ہوا گرم پانی پلایا جائے گا.گرم پانی
انسان دو ہی حالتوں میں پیتا ہے یا تو اس وقت جب بیمار ہو اور علاج کے لئے اُسے گرم پانی پینا
پڑے اور یا پھر اُس وقت جب ٹھنڈا پانی اُسے میسر نہ آئے اور مجبوراً گرم پانی پینا پڑے.(گو
اس زمانہ میں لوگوں میں چائے کا طریق مروج ہو گیا ہے جو گرم بھی ہوتی ہے اور پیاس بجھانے
کے لئے بھی استعمال کی جاتی ہے مگر وہ در حقیقت ایک غذا ہے.پانی کا قائمقام نہیں ) پس گرم
پانی پینے کا ذکر فرما کر اس طرف اشارہ کیا ہے کہ وہ ہر آرام سے محروم ہو جائیں گے یا یہ کہ ان کی
روحانی امراض کو دور کرنے کے لئے انہیں ابتلاؤں میں ڈالا جائے گا اور ایسے گرم چشمہ سے
اُن کو پانی پلایا جائے گا جس کی گرمی انتہا درجہ تک پہنچی ہوئی ہوگی.یعنی پانی پینے کی جو اصل
غرض ہوتی ہے کہ انسانی جسم پر تر و تازگی آئے وہ اُن کو حاصل نہیں ہوگی.دُنیا میں دو قسم کی
چیزیں ہیں.ایک تو ایسی ہیں جو نضارت اور تر و تازگی پیدا کرتی ہیں اور ایک ایسی ہیں جو موٹاپا
پیدا کرتی ہیں.ان میں سے ایک مقصد غذا سے اور دوسرا مقصد پانی سے حاصل ہو جاتا ہے.پانی پینے سے تروتازگی حاصل ہوتی ہے اور غذا کھانے سے بھوک دور ہوتی اور جسم فربہ ہوتا
ہے.کفار کے متعلق بتایا کہ اُن کو یہ دونوں باتیں حاصل نہیں ہوں گی.نہ اُن کے اندر تازگی
پائی جائے گی.اور نہ اُن کے جسم پر گوشت چڑھے گا یعنی اُن کے دل بھی مرجھا جائیں گے اور
713
Page 722
اُن کے جسم بھی مرجھا جائیں گے.کھولتا ہوا چشمہ آخرت میں تو ہوگا ہی.دنیا میں کھولتے ہوئے چشمہ سے مراد وہ چیز ہوتی
ہے جس سے دل کو آگ لگ جائے.مطلب یہ ہے کہ کفار کو ایسے مصائب پہنچیں گے اور
ایسے حالات میں سے وہ گزریں گے کہ اُن کے دل جل جائیں گے.یہ عَيْنِ انيَة ہی تھا کہ اُن
کی اولاد میں مسلمان ہو گئیں اور جس مذہب کو مٹانے کے لئے وہ کھڑے ہوئے تھے اسی
مذہب میں اُن کے بیٹے شامل ہو گئے.جب وہ اپنی اولادوں کو اسلام میں شامل
ہوتے دیکھتے ہوں گے تو کس طرح اُن کے دل جلتے ہوں گے کہ ہم کیا چاہتے تھے اور کیا ہو
گیا.ہمارے ہاں بھی محاورہ کے طور پر کہا جاتا ہے کہ میں تو غم کے گھونٹ پی رہا ہوں.گویا غم
کی چیزوں کو بھی پینے سے مشابہت دی جاتی ہے.عربی زبان میں بھی غم کے گھونٹ پینا محاورہ
کے طور پر استعمال ہوتا ہے.پس فرماتا ہے اُن کو گرم اور تیز گھونٹ پلائے جائیں گے.یعنی
ایک طرف اُن کی اولادیں اور دوسری طرف غلام مسلمان ہونے لگ جائیں گے جس کا اُن کو
شدید صدمہ پہنچے گا.قرآن کریم میں اس حقیقت کو دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں بیان
فرمایا ہے اَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ تَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطرافها (الرعد 42) یعنی یہ لوگ جو کہتے
ہیں کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غالب آجائیں گے، آپ کے دین کو مٹادیں گے اور
مسلمانوں کو شکست دے دیں گے، کیا ان اندھوں کو یہ بات نظر نہیں آتی کہ ہم زمین کو اُس
کے کناروں سے چھوٹا کرتے چلے آرہے ہیں.ادھر غلام اسلام میں داخل ہورہے ہیں اور
اُدھر نوجوان اسلام کو قبول کر رہے ہیں.جب غلام اور نوجوان دونوں اسلام میں داخل ہو گئے تو
پیچھے سوائے بڑھوں کے کون رہ جائے گا.یہ بُڈھے چند سالوں میں مر کر فنا ہو جائیں گے اور ان
کی نسلیں اسلام میں شامل ہو جائیں گی.دنیا میں طاقت کے یہی دوز رائع ہوتے ہیں.ایک
غلام جو ہاتھ ہوتے ہیں اور دوسری آئندہ نسلیں جو جڑ ہوتی ہیں.جب اُن کے پاس نہ ہاتھ رہے
اور نہ جڑ تو درمیان کا ٹھنڈ کیا کرے گا.714
Page 723
غرض اس آیت میں اللہ تعالیٰ اسلام کی ترقی کی خبر دیتے ہوئے فرماتا ہے ان کفار کو
عَيْنٍ انية یعنی گرم چشمہ سے گھونٹ پینے پڑیں گے اور یہ ایسی خبریں سنیں گے جن سے ان
کے سینے جلنے لگ جائیں گے.ہم دیکھتے ہیں کہ واقعہ میں اگر کوئی شخص کسی مذہب کو سچے دل
سے قبول کرتا ہے تو اس کی اولاد کا اس سے پھرنا اس کے لئے انتہائی طور پر ڈکھ کا موجب ہوتا
ہے.عقلی طور پر اگر اولا د مذہب سے منحرف ہو جاتی ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں،
مذہب کے معاملہ میں جبر سے کام نہیں لیا جا سکتا.حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا اگر اُن کا
مخالف ہو سکتا ہے تو دوسرے لوگوں کی اولادیں بھی اپنے باپ دادا کے مذہب سے انحراف
اختیار کر سکتی ہیں.مگر جہاں کوئی اور قائم مقام نہ ہو اور وہ اولا دجس سے انسان کی امیدیں وابستہ
ہوں اپنے باپ دادا کے مذہب کو ترک کر دے تو یہ ایک ایسا تلخ گھونٹ ہے جس کا پینا انسانی
طاقت برداشت سے بالکل باہر ہوتا ہے.غرض اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ کفار ایسے حالات میں سے گذریں گے کہ اُن کو بڑے
بڑے تلخ گھونٹ پینے پڑیں گے.یہ سورۃ دونوں زمانوں کے ساتھ تعلق رکھتی ہے.اسلام کے ابتدائی زمانہ کے ساتھ بھی
اور موجودہ زمانہ کے ساتھ بھی.تُشفى مِن عَيْنٍ آنِيَةٍ میں کفار کے متعلق اللہ تعالیٰ کی طرف سے
جو خبر دی گئی تھی وہ اس زمانہ میں بھی بڑی صفائی کے ساتھ پوری ہوتی ہے.الطَّرِيعُ الطَّرِيعُ نَبَاتُ رَطْبُهُ يُسمى شِبْرَقًا وَيَابِسُهُ ضَرِيعًا لَا تَقْرُبُهُ دَابَّةٌ
لخبيثه.یعنی ضریع گھاس کی ایک قسم ہوتی ہے جب تک وہ گھاس تازہ رہے اُسے شہرق کہتے
ہیں اور جب سوکھ جائے تو ضریع کہتے ہیں.ضریع ایسی گندی چیز ہوتی ہے کہ جانور بھی اس کو
نہیں کھاتے.اسی طرح ضریح ایسی گھاس کو بھی کہتے ہیں جو سمندر کے کنارے اگ آتا ہے مگر
چونکہ نہایت گندہ اور بد بودار ہوتا ہے لوگ اسے کاٹ کر پانی میں بہا دیتے ہیں.اسی طرح ہر
درخت کی سوکھی ٹہنی یا سوکھے پتوں کو بھی ضریح کہتے ہیں.اسی طرح سڑے ہوئے پانی میں
ایک بوٹی ہوتی ہے اس کو بھی ضریع کہتے ہیں.(اقرب)
715
Page 724
لغت والوں نے جو اس کی تشریح کی ہے اُس سے میں سمجھتا ہوں کہ غالبا اس سے کائی مراد
ہے کیونکہ وہ لکھتے ہیں نَبَاتُ فِي الْمَاءِ الْآجَنِ لَهُ عُرُوقُ لَا تَصِلُ إِلَى الْأَرْضِ سڑے ہوئے
پانی میں ایک بوٹی ہوتی ہے جس کی جڑیں زمین میں نہیں جاتیں ، پانی میں ہی رہتی ہیں.یہ
ساری چیزیں ایسی ہیں جن میں کوئی غذائیت نہیں ہوتی اور جنہیں انسان چھوڑ جانور بھی نہیں
کھاتے.پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَيْسَ لَهُمْ طَعَامُ إِلَّا مِنْ ضَرِيع کہ ان کو سوائے ضريع
کے اور کوئی کھانا نہیں ملے گا.قرآن کریم کا اسلوب بیان اور اُس کے الفاظ واضح کر رہے ہیں کہ ان کو کھانے کے لئے
ضریع دیا جائے گا.یعنی وہ ایسے ذلیل ہو جائیں گے کہ ایسی چیزیں کھانے پر مجبور ہوں گے جن
کو جانور بھی نہیں کھاتے.مطلب یہ ہے کہ ان کو ایسی ایسی ذلتیں اور رسوائیاں پہنچیں گی جن کو
ادنی ادنی انسان بھی برداشت نہیں کر سکتے.فتح مکہ کے بعد کئی آدمی جنگلوں میں بھاگ کر چلے
گئے تھے اور وہیں مر گئے.پھر بعض لوگ تھے جو بڑی بڑی تلخیاں برداشت کرنے کے بعد مکہ
میں واپس آئے اور انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی جس پر رسول کریم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں معاف فرما دیا.جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ
فتح کر لیا تو وہ لوگ جو کہا کرتے تھے کہ ہم مسلمانوں کو تباہ کر دیں گے.ان کو کچل کر رکھ دیں
گے.اُن کو مٹادیں گے.جب اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوں گے کہ مسلمان غلام اُن کے حاکم
اور سردار بنے ہوئے ہیں تو خواہ وہ اعلیٰ درجہ کا کھانا ہی کیوں نہ کھاتے ہوں مگر وہ انہیں ضریع سے
کم محسوس نہیں ہوتا ہوگا اور وہ کھانا اُن کے انگ میں نہیں لگتا ہوگا.یہ ضروری نہیں کہ ضریع سے
مراد یہاں حقیقتا شبرق گھاس ہی ہو بلکہ آگے جو تشریح کی گئی ہے کہ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ
جوع وہ کھانا نہ اُن کو موٹا کرے گا اور نہ اُن کی بھوک کو دور کرے گا یہ اُن کی بدحواسی کی حالت کو
ظاہر کر رہا ہے.پس بالکل قرین قیاس ہے کہ ضریع کا ذ کر استعارہ ہے.وہ روزانہ دیکھتے تھے کہ مسلمان ترقی کر رہے ہیں اور ہم شکست کھاتے جا رہے ہیں.پھر ہر
لڑائی میں انہیں خبریں پہنچتی تھیں کہ آج فلاں رئیس مر گیا ہے.آج فلاں سردار مر گیا ہے یا
716
Page 725
آج فلاں قوم مسلمانوں سے مل گئی ہے اور فلاں قوم نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے.یہ خبریں اُن
کے لئے اس قدر پریشان گن ، اس قدر تکلیف دہ اور اس قدر غم والم میں مبتلا کرنے والی تھیں کہ
واقعہ میں اچھی سے اچھی غذائیں کھا کر بھی وہ اُن کے انگ نہیں لگ سکتی تھیں.الغرض ليس
لَهُمْ طَعَامُ إِلَّا مِنْ طَرِيعِ لَّا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِى مِنْ جُوع اور اسی طرح تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ
میں اسلام کی ترقیات کے متعلق زبر دست پیشگوئی کی گئی ہے.غور کرو اور سوچو کہ کیسے نازک وقت میں اسلام کی ترقی کی یہ عظیم الشان خبر دی گئی تھی کہ
یہ لوگ تو الگ رہے ان کے سردار بھی مسلمانوں کے مقابلہ میں کچھ نہیں کر سکتے.اُس وقت
ظاہری حالات کے لحاظ سے کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ مسلمان اپنے گھروں سے باہر نکل
کر نمازیں پڑھ سکیں گے فتح و غلبہ تو ڈور کی بات ہے مگر ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ کی طرف
سے خبر دی گئی کہ مسلمان کامیاب ہوں گے.دشمن نا کام ہوگا اور انہیں تیز گرم پانی کے گھونٹ
بار بار پینے پڑیں گے.مسلمانوں کی مظلومیت اور اُن کی کمزوری اس قدر بڑھی ہوئی تھی کہ
جنگ احزاب تک یہ حالت تھی جس کا حدیثوں میں ذکر آتا ہے اور قرآن کریم میں بھی اس کی
طرف اشارہ پایا جاتا ہے کہ منافق مسلمانوں کو طعنے دیتے تھے کہ تمہیں پاخانہ پھرنے کو تو جگہ
نہیں ملتی اور فتح کی خبریں سُنائی جارہی ہیں.یہ غلبہ کی پیشگوئی چوتھے سال بعد نبوت میں کی گئی
ہے اور ہجرت کے پانچویں سال تک مسلمانوں کی کمزوری کی یہ حالت تھی جس کا اوپر ذکر کیا گیا
ہے.پس اتنا لمبا عرصہ پہلے اسلام کے غلبہ اور مسلمانوں کی شان وشوکت کے متعلق خبر دے
دینا یقینا کسی انسان کا کام نہیں ہوسکتا.غرضِ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامُ إِلَّا مِنْ طَرِيحٍ لَّا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِی مِنْ جُوعٍ میں بتایا گیا ہے کہ
اُن کا کھانا اور اُن کا پانی اُن کے لئے عذاب بن جائے گا اور غم اور مصیبت اُن پر نازل ہوگی.گویا استعارہ یہ ویسا ہی کلام ہے جیسے ایک شاعر کہتا ہے
محون دل پینے کو اور لخت جگر کھانے کو
یہ غذا ملتی ہے لیلیٰ تیرے دیوانے کو
717
Page 726
پانی پئیں گے اور وہ آگ معلوم ہو گا خواہ ٹھنڈا پانی پیئیں لیکن وہ اُن کے گلے میں پھنسے گا اور
انہیں جلائے گا جیسے غم اور مصیبت میں لوگ پانی پیتے ہیں تو وہ اُن کے گلے میں پھنستا ہے.دودھ دے دو.عمدہ سے عمدہ کھانا دے دو.اچھی سے اچھی غذائیں کھلاتے جاؤ اُن کا کوئی فائدہ
نہیں ہوتا بلکہ غم سے انسان اور زیادہ دُبلا ہوتا جاتا ہے.پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مخالفین
اسلام پر اس قدر مصائب و مشکلات آئیں گی.اس قدر ان کی عزتوں پر حملے ہوں گے.سیاسی
حملے ہوں گے.خاندانی حملے ہوں گے کہ اُن کو تلخی کے گھونٹ پینے پڑیں گے اور لخت جگر کھانے
کو ملیں گے.ٹھنڈا پانی پیئیں گے لیکن وہ ان کے منہ میں آبلے ڈال دے گا.عمدہ سے عمدہ
کھانے کھائیں گے لیکن وہ انہیں اتنا نفع نہیں دیں گے جتنا خشک پتے یا شبرق گھاس اونٹ
کو نفع دیتے ہیں.وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ
ناعمة نعم سے اسم فاعل مؤنث کا صیغہ ہے اور نَعَمَ الرَّجُلُ کے معنے ہیں رَفِهَ.وہ
خوشحال اور آسودہ حال ہو گیا.اور جب نعم عیشہ کہیں تو معنے ہوتے ہیں طَابَ وَلَانَ
وَاتَّسع.یعنی اس کی زندگی عمدہ ہو گئی اور کسی تکلیف کا سامنا اُسے نہ کرنا پڑا.اور ہر چیز اُسے
با فراغت ملنے لگی (اقرب) بحر محیط کے مصنف نے ناعمہ کے معنے بحسن ونضارت والے کے
کئے ہیں اور پھر لکھا ہے کہ ناعمة کے معنے مُتَنَغِبَة کے بھی ہوتے ہیں.یعنی یہ معنے بھی ہیں کہ
اُن میں حسن اور نضارت اور تا زگی پائی جائے گی اور ان کے چہرے خوبصورت ہوں گے اور یہ
بھی معنے ہیں کہ انہیں بڑی بڑی نعمتیں حاصل ہوں گی ( محیط)
پہلی آیت میں وجوہ کا ذکر تھا جن کی صفت یہ تھی کہ وہ عَامِلة اور ناصبة تھے.یعنی
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں یا آنے والے ماموروں کے مقابلہ میں خوب عمل کرنے
والے اور تھکا دینے والی محنت کرنے والے تھے انفرادی رنگ میں بھی اور اجتماعی رنگ
میں بھی.مگر اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ باوجود ان کے انفرادی اور اجتماعی مقابلوں کے یہ
718
Page 727
نہیں ہوگا کہ خدا کا رسول دب جائے یا اکیلا رہ جائے بلکہ اُس کی جماعت بڑھتی چلی جائے گی
اور وہ جماعت ایسی ہوگی جو دنیا میں عزت اور کامیابی حاصل کرنے والی ہوگی.چنانچہ انہی کا ذکر
وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ میں کیا گیا ہے.سرداران کفار کو وجوہ اس لئے کہا گیا تھا کہ وہ ابتداء میں وُجُودٌ تھے گو بعد میں خَاشِعَة
ہو گئے.اور جولوگ گر جائیں، لوگوں کی نگاہ میں ذلیل ہو جائیں، اُن کی آواز میں کوئی اثر نہ
رہے اور وہ غم والم کی آگ میں ہر وقت جلتے رہیں وہ وجوہ نہیں رہتے.پس اُن کا نام وُجُوهٌ
اُن کی ابتدائی حالت کی وجہ سے رکھا گیا تھا.کیونکہ شروع میں وہ واقعہ میں سرداران قوم میں
سے تھے.بڑی عزت اور وجاہت رکھتے تھے.مگر مسلمانوں کا نام وجود اُن کی انتہا کی وجہ سے
رکھا گیا ہے.پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کام وہی اچھا ہوتا ہے جس کا انجام اچھا ہو.کافر
وُجُوا بن کر اٹھے اور خاشعة بن کر رہ گئے.مگر مومن گری ہوئی حالت سے اُٹھے اور وجونا بن
گئے.ہر قسم کی عزت ، رتبے اور درجے اُن کو حاصل ہو گئے.وجوہ کے ساتھ کاعمة کا لفظ بڑھا دیا اور ناعمة کے دو معنے بتائے جاچکے ہیں حسن و
نضارت والے اور یہ بھی کہ وہ متنعمة ہوں گے.یعنی بڑی بڑی نعمتیں اُن کو حاصل ہوں گی.ذاتی طور پر بھی وہ کمال رکھیں گے اور ماحول کے لحاظ سے بھی کمال رکھیں گے.جہاں اُن کو
ذاتی طور پر بھی وہ عمتیں حاصل ہوں گی وہاں اللہ تعالیٰ اُن کو بیرونی نعمتیں بھی عطا کرے گا.ظاہری معنوں کے لحاظ سے یہ مراد ہوگی کہ وہ حسین ، خوبصورت اور صاحب اموال ہوں گے اور
روحانی لحاظ سے یہ معنے ہوں گے کہ وہ متقی اور صاحب علوم ہوں گے.یعنی متقی بھی ہوں گے اور
علوم روحانیہ بھی اُن کو حاصل ہوں گے.اپنی ذات میں بھی کامل عرفان اور استغنا اُن کو حاصل
ہوگا اور اُن کے پاس ایسے علوم اور اموال بھی ہوں گے جو دوسروں کو سکھا سکیں اور دے سکیں.محسن ایک ذاتی چیز ہے اور مال ایسی چیز ہے جو دوسرے کو دی جاسکتی ہے.اسی طرح تقویٰ
ایسی چیز ہے جو انسان کسی کو نہیں دے سکتا لیکن علم ایسی چیز ہے جو دوسرے کو دے سکتا ہے.719
Page 728
پس بتایا کہ جیسے ظاہری لحاظ سے محسن اور مال دونوں نعمتیں اُن کو حاصل ہوں گی اسی طرح باطنی
لحاظ سے تقویٰ بھی اُن میں پایا جائے گا اور علم بھی اُن کو عطا ہو گا.ظاہری لحاظ سے وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ
ناعمة کے یہ معنے ہوں گے کہ وہ اُس دن بڑے حسین نظر آرہے ہوں گے.بظاہر یہ سمجھنا مشکل
معلوم ہوتا ہے کہ کسی خاص وقت کوئی شخص حسین کس طرح ہو جائے گا.مگر حقیقت یہ ہے کہ
جس کے ساتھ محبت کا تعلق ہو وہ بہت ہی خوبصورت دکھائی دیتا ہے اور اس آیت میں اسی
طرف اشارہ ہے کہ بوجہ ذاتی تقویٰ اور احسان کے وہ لوگوں کے محبوب ہو جائیں گے اور خواہ
اُن کی شکل کیسی ہی ہو وہ لوگوں کو حسین نظر آئیں گے جیسے ہر باپ کو اپنا بیٹا اور ہر بیٹے کو اپنا باپ
حسین نظر آتا ہے.غرض ناعمة کے اگر ظاہری معنے لئے جائیں تو وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ کا مفہوم یہ ہوگا کہ وہ
ایسے مقبول جہاں ہو جائیں گے کہ لوگوں کو حسین نظر آنے لگ جائیں گے.یہ ضروری نہیں کہ
اُن کی شکلیں بھی حسین ہوں بلکہ وہ دنیا کو حسین اور خوبصورت معلوم ہونے لگ جائیں گے.جب وہ دنیا کے محسن ہوں گے جب وہ خدمت خلق کرنے والے ہوں گے جب وہ یتامیٰ سے
حسن سلوک کرنے والے ہوں گے، جب وہ غریبوں سے ہمدردی کرنے والے ہوں گے،
جب وہ گرے ہوئے لوگوں کو اٹھانے والے ہوں گے تو وہ لوگ دنیا کو دوسرے لوگوں کی
نسبت زیادہ خوبصورت اور اچھے نظر آنے لگ جائیں گے اور دوسرے لوگوں کے چہرے اُن
کے مقابلہ میں انہیں حسین نظر نہیں آئیں گے.پس اگر ہم اس کے ظاہری معنے لیں تب بھی وہ صحیح ہوں گے مگر اس طرح نہیں کہ ان کی
شکلیں خوبصورت ہو جائیں گی بلکہ جیسے محاورہ کے طور پر کہتے ہیں پر نالہ چلتا ہے اور مراد یہ ہوتا
ہے کہ پر نالہ میں پانی چلتا ہے.اسی طرح اس کا یہ مطلب ہوگا کہ وہ اپنے احسان کی وجہ سے
حسین نظر آنے لگ جائیں گے.جب اُن میں احسان کا مادہ ہوگا ، جب اُن میں نیکی ہوگی، جب
اُن میں عفت ہوگی، جب اُن میں حسنِ سلوک کا جذبہ ہوگا تو و ہ لوگوں کو بے انتہا پیارے لگنے
720
Page 729
لگ جائیں گے.پس وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ میں صحابہ کے یا مومنوں کے اخلاق فاضلہ کی
طرف اشارہ ہے یعنی ایسے اعلیٰ درجہ کے اخلاق اور حسن سلوک کی خُدا ان کو تو فیق عطا فرمائے
گا کہ وہ دنیا کی نگاہ میں بڑے خوبصورت اور حسین نظر آئیں گے.اور اگر اس سے تقویٰ اور علم
مراد ہو تو وہ ظاہر ہی ہے اس کی تشریح کی ضرورت نہیں.وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ لِسَعْيِهَا رَاضِيَةً کا اگر ہم معنوی لحاظ سے ترجمہ کریں تو یوں ہوگا
کہ کچھ چہرے ایسے ہوں گے یا کچھ افراد ایسے ہوں گے کہ ایک دن آئے گا جب کہ وہ دنیا کی
نگاہ میں حسین ہو جائیں گے لِسَعيها راضية اور اپنی نگاہ میں بھی حسین ہوں گے اور وہ اپنے
کئے پر خوش ہوں گے.اُن میں یہ احساس نہیں ہوگا کہ ہم نے لوگوں کے لئے قربانی کر کے
اپنے اوپر ظلم کیا ہے بلکہ وہ جس قدر خدمات سرانجام دیں گے،جس قدر قربانیاں کریں گے،
جس قدر احسانات کریں گے اُن کے دل اور زیادہ خوش ہوں گے.گویا ایمان اور اخلاص اور
محبت باللہ سے اُن کے قلوب اس طرح پر ہوں گے کہ صرف لوگ ہی اُن کو دیکھ کر خوش نہیں
ہوں گے بلکہ وہ خود بھی اپنے کاموں کو دیکھ کر خوش ہوں گے.فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ
پرانے زمانہ میں شاید جَنَّةٍ عَالِيَةٍ کا مفہوم پوری طرح نہ سمجھا جاتا ہومگر اس زمانہ میں
اس کا مفہوم سمجھنا بالکل آسان ہے کیونکہ بینگنگ گارڈنز (HANGING GARDENS) دنیا میں
پائے جاتے ہیں.ہینگنگ گارڈن کا یہ مطلب نہیں کہ وہ لٹکا ہوا ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ وہ اونچی چوٹی پر ہے
اور چونکہ لوگ نیچے ہوتے ہیں اور باغات چوٹی پر ہوتے ہیں اس لئے اُن کو ہینگ گارڈنز کہا
جاتا ہے یعنی بلند اور اونچے باغات.اسی طرح فرماتا ہے مومن ایسے باغات میں ہوں گے جو
اونچے اور بلند ہوں گے.جنت کے معنے سایہ دار جگہ کے ہیں اور عالیہ کے معنے بلند کے ہیں.جو چیز سایہ دار ہو اُس
721
Page 730
کے اندر کی چیزیں لوگوں کو نظر نہیں آتیں اور جو چیز بلندی پر ہو اُس پر دھوپ پڑتی ہے سایہ دار
نہیں رہ سکتی.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جن باغات کا ہم ذکر کرتے ہیں اُن کے اندر دونوں قسم کی
خوبیاں پائی جائیں گی.جہاں تک شہرت اور عزت کا سوال ہے وہ عالیہ ہوں گے.اور جہاں
تک اُن کی نیکیوں اور خوبیوں کا سوال ہے وہ سایہ دار ہوں گے.یعنی لوگوں کی نظریں بھی اُن کی
طرف اُٹھیں گی اور پھر وہ تمازت اور دھوپ کا شکار بھی نہیں ہوں گے بلکہ ہر وقت سائیۃ
رحمت الہی کے نیچے رہیں گے ورنہ اکثر لوگ بلندی پر پہنچ کر ننگے ہو جاتے ہیں اور خدا تعالیٰ کے
فضل کا سورج بجائے اُن کے نفع مند ہونے کے لئے اُن کے جلانے کا موجب ہو جاتا ہے.لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةً
لاغِيَةً کے معنے ہیں اللغو یعنی لغو اور بیہودہ بات.کہتے ہیں كَلِمَةٌ لَاغِيَةٌ آنی فَاحِشَةً
كَلِمَةٌ لَاغِيَةً ایسے کلمہ کو کہتے ہیں جوش اور بُرا ہو وَمِنْهُ لَا تَسْمَعُ فِيْهَا لَاغِيَةً أَىٰ كَلِمَةٌ ذَاتَ
لَغْوِ اور لَا تَسْمَعُ فِيهَا لاغِيَةً کے یہ معنے ہیں کہ تو اس میں کوئی محش اور بُری بات نہیں سنے گا یا
وہ چہرے اس میں کوئی لغو بات نہ سنیں گے ( اقرب)
دنیا میں انسان دو ہی طرح بری باتیں سنتا ہے یا تو اس طرح کہ وہ خود کج رو ہوتا ہے اور
لوگوں سے لڑتا رہتا ہے اس کے نتیجہ میں لازمی طور پر اُسے لاغية سُننا پڑتا ہے.مثلاً جب وہ
دوسرے کو خبیث کہے گا تو خبیث کا لفظ اُس کے اپنے کان میں بھی پڑے گا.اور اس طرح اُسے
لاغية سُننا پڑے گا.اور یا پھر دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ لوگ اس سے لڑتے ہیں اور وہ
لاغية سنتا ہے.اپنا کہا انسان تب سنتا ہے جب وہ لوگوں سے خوش نہ ہو.اور لوگوں سے
لاغية تب سنتا ہے جب لوگ اس سے خوش نہ ہوں.مگر فرماتا ہے وہ لوگ ایسے ہوں گے کہ
لاغية نہیں سنیں گے.یعنی وہ لوگوں سے خوش ہوں گے اور لوگ اُن پر خوش ہوں گے.اُن
میں رحم ہوگا ، اُن میں ہمدردی ہوگی ، اُن میں پردہ پوشی کی عادت ہوگی، ان میں حسن سلوک کا جذبہ
ہوگا، اُن میں محبت ہوگی، اُن میں خلوص ہوگا اور اس وجہ سے وہ لوگوں سے لڑیں گے نہیں اور نہ
722
Page 731
اُن کو گالیاں دیں گے.جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق احادیث میں آتا ہے کہ
آپ نہ سناب تھے اور نہ لکان.نہ گالیاں دیتے تھے اور نہ لوگوں پر لعنتیں ڈالتے تھے.جب
انسان کا مزاج چڑ چڑا ہو جاتا ہے یا بخیل اور ضدی ہوتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں
سے لڑتا ہے اور گالی گلوچ دیتا ہے.چنانچہ بعض لوگوں میں یہ نقص ہوتا ہے کہ کسی کام کے لئے
لوگ اُن کے پاس جائیں تو وہ شور مچادیتے ہیں کہ یہ بد بخت ہر وقت پیچھے پڑے رہتے ہیں.کسی وقت چھوڑتے بھی نہیں.لیکن اگر کوئی سخی ہوتا ہے حسن سلوک کرتا ہے، لوگوں سے محبت
کے ساتھ پیش آتا ہے تو اپنے منہ سے لغو بات نہیں سنتا اور اگر وہ حسن سلوک میں کامل ہو اور اس
کے ساتھ ہی اُسے طاقت اور غلبہ بھی حاصل ہو تو وہ اور لوگوں سے بھی لاغيّة نہیں سنتا.در حقیقت دوسروں سے لاغية نہ سننے میں مسلمانوں کی طاقت اور اُن کی قوت کی طرف بھی
اشارہ کیا گیا ہے کیونکہ دنیا میں ایسے کمینے لوگ بھی پائے جاتے ہیں کہ خواہ اُن سے کس قدر
حسنِ سلوک کیا جائے وہ بُرا بھلا کہنے سے باز نہیں آتے.ہماری جماعت کو ہی دیکھ لو.ہم کس قدر لوگوں سے سلوک کرتے ہیں اور ان کی بہتری کی
کوششیں کرتے ہیں مگر سب سے زیادہ گالیاں ہمیں ہی ملتی ہیں.تو بعض لوگ ایسے گندے ہو
جاتے ہیں کہ کسی حالت میں بھی نیش زنی سے باز نہیں آتے.جس طرح عقرب کا یہ کام ہوتا ہے
کہ وہ نیش زنی کرتا ہے اسی طرح بعض لوگ شیطان کے ورغلانے سے اتنے گندے ہو جاتے
ہیں کہ اپنے نفع اور نقصان کو بھی نہیں دیکھتے اور خدا تعالیٰ کی طرف سے آنے والے پیغام کی
پوری مخالفت کرتے ہیں خواہ اس پیغام کو پیش کرنے والے
کتنی ہمدردی اور محبت سے کام لے
رہے ہوں.لیکن اگر الہی جماعت کو حکومت اور غلبہ میسر آجائے تو پھر وہی لوگ بُوٹ چاٹنے
لگ جاتے ہیں.پس لا تَسْمَعُ فِيهَا لاغِيَةً میں مسلمانوں کی حکومت کی طرف بھی اشارہ کیا گیا
ہے اور بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کو ایسا غلبہ حاصل ہو جائے گا کہ اُن کے مقابلہ میں کوئی شخص
بُری باتیں کہنے کی جرات نہیں کرے گا.اسی طرح لَا تَسْمَعُ فِيْهَا لَاغِيَةً میں مسلمانوں کے
723
Page 732
اخلاق کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے جس طرح لسعيها رَاضِيَةً میں تین باتوں کا ذکر کیا گیا
تھا.مسلمانوں کا اپنے نفس سے سلوک، مسلمانوں کا بنی نوع انسان سے سلوک اور مسلمانوں کا
خدا تعالیٰ سے سلوک.اور بتایا گیا تھا کہ وہ تینوں لحاظ سے کامل ہوں گے.اسی طرح لا تسمعُ
فيها لاغِيَةً میں اوّل اُن کے اخلاق کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ وہ بخیل اور
حریص نہیں ہوں گے کہ اگر انہیں لوگوں سے حسن سلوک کرنا پڑے تو وہ گالیاں دینے پر اُتر
آئیں.یا اُن کے مزاج میں چڑ چڑا پن نہیں ہوگا کہ لوگ انہیں برا کہیں.بلکہ وہ لوگوں کے
محسن ہوں گے، منعم ہوں گے، معلم ہوں گے اور لوگ اُن کی تعریف کریں گے.لیکن کمینے
انسان کی یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ دونوں حالتوں میں لڑتا ہے.اُس پر احسان کرو تب بھی لڑتا
ہے.نہ کرو تب بھی لڑتا ہے گویا اُس کی حالت گتے کی طرح ہوتی ہے کہ ان تخیل عَلَيْهِ
يَلْهَثْ اَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ (الاعراف (177) دونوں حالتوں میں زبان نکالے کتے کی طرح پیچھے
پڑا رہتا ہے.ایسا انسان اسی صورت میں خاموش ہوتا ہے جب اُس کے مد مقابل کو حکومت
اور غلبہ میسر آجائے.پس فرماتا ہے مسلمانوں کو غلبہ مل جائے گا اور کوئی صورت لاغية سننے کی
نہیں رہے گی.دشمنان دین جو احسان فراموش ہیں وہ غلبہ کی وجہ سے تعریف کریں گے
اور یہ خود نیک طبیعت ہونے کی وجہ سے کسی سے بدگوئی نہیں کریں گے اس لئے لغو ان کو سُنائی
ہی نہیں دے گا.فِيْهَا عَيْن جَارِيَةٌ
مومن جبس جنت میں رہیں گے.اُس میں ایک جاری چشمہ ہوگا.اگلے جہان میں تو یہ
ہوگا ہی.اس کے متعلق کسی تفصیل کی ضرورت نہیں.نہ میں نے اسے دیکھا ہے اور نہ کسی اور
نے.یہ ایک ایمانی معاملہ ہے.لیکن دنیا کے لحاظ سے یہ معنے ہیں کہ وہ ایسے علوم اپنے ورثہ میں چھوڑیں گے اور ایسے سلوک
بنی نوع انسان سے کریں گے جن کا اثر عرصہ دراز تک چلتا چلا جائے گا.کچھ لوگوں کا احسان
724
Page 733
صرف وقتی ہوتا ہے لیکن کچھ لوگوں کا احسان صدقہ جاریہ کا رنگ اپنے اندر رکھتا ہے.مثلاً کسی
غریب کو ایک پیسہ دے دینا یہ بھی احسان ہے.مگر جب وہ اُس پیسے سے روٹی خرید کر کھا لیتا
ہے تو اس احسان کا دائرہ ختم ہو جاتا ہے.لیکن ایک احسان یہ ہے کہ کسی کو دین کی باتیں
سکھائی جائیں یا اخلاقی لحاظ سے اعلیٰ تربیت دی جائے.یہ احسان بڑا وسیع ہے.یا مثلاً کسی کو
کوئی پیشہ سکھا دینا یا کسی کو کوئی پیشہ چلانے کے لئے مدد دے دینا یا اُسے اپنے پیشہ کے
چلانے کے لئے ہتھیار خرید دینا یہ احسان اپنے اندر بہت بڑی وسعت رکھتا ہے.روٹی دے
دینا اور قسم کا احسان ہے اور پیشہ سکھا دینا یا پیشہ چلانے کے لئے روپیہ سے امداد کرنا یا ہتھیار
و غیر خرید دینا یہ اور قسم کا احسان ہے.پہلی قسم کا صدقہ ختم ہو گیا مگر یہ صدقہ صدقہ جاریہ ہے.فِيهَا عَيْن جَارِيَةٌ سے یہی مراد ہے کہ ان کے صدقات صدقات جاریہ ہوں گے اور ان کے
احسان بنی نوع انسان سے محدود نہیں ہوں گے یا معمولی اور چھوٹے درجہ کے نہیں ہوں گے.بلکہ ایسے ہوں گے جو عرصہ دراز تک چلتے چلے جائیں گے.جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم سے صحابہ نے علم لیا.اور پھر اُسے دنیا میں اس طرح پھیلا یا کہ عَنْ فُلانٍ عَن فُلانٍ کے
ایک لمبے سلسلہ کے ماتحت وہ انگلی نسلوں تک پہنچ گئے.اگلوں نے اگلوں تک اور پھر اگلوں
نے اگلوں تک یہاں تک کہ وہ سارے علوم ہم تک پہنچ گئے.اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام میں یہ
خوبی بدرجہ اتم رکھی ہوئی تھی کہ وہ علوم کے خزانے صرف اپنے تک محدود نہیں رکھتے تھے بلکہ
دوسروں تک عَيْن جَارِيَةٌ بن کر پہنچا دیتے تھے.لوگوں کے پاس علم ہوتا ہے تو وہ اُس کو بند کر
لیتے ہیں.مگر صحابہ کی یہ حالت تھی کہ ایک صحابی سے ایک دفعہ کسی نے کوئی بات پوچھی.اُس
نے جواب
دیا کہ مجھے تو یہ بات معلوم نہیں لیکن اگر مجھے معلوم ہوتی اور میری گردن پر کوئی شخص
تلوار رکھ کر کہتا کہ اب میں تجھے قتل کرنے لگا ہوں تو میں اس کی تلوار چلنے سے پہلے جلدی جلدی
بتا دیتا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے میں نے فلاں فلاں بات سُنی ہوئی ہے.یہ عین
جَارِيَةٌ ہی تھے کہ کسی جگہ لکتے نہیں تھے بلکہ بہتے چلے جاتے تھے.725
Page 734
پھر عَيْن جَارِيَةٌ میں یہ خبر بھی دی گئی تھی کہ صحابہ اور اُن کے شاگردڈ ورڈ ور تک نکل جائیں
گے.صرف عرب میں محدود نہیں رہیں گے.چنانچہ دیکھ لو مسلمان عرب سے نکلے اور دنیا کے
دور دراز ممالک تک پھیل گئے یہاں تک کہ وہ چین بھی گئے اور انہوں نے اسلام پھیلایا.انطاکیہ میں بھی گئے اور اسلام پھیلایا.سپین میں بھی گئے اور اسلام پھیلایا.غرض وہ دنیا کے
کناروں تک نکل گئے اور دنیا میں علوم کے دریا انہوں نے بہا دیئے.جس طرح جاری چشمہ کا
پانی ڈور ڈور کی زمین کو سیراب کر دیتا ہے اسی طرح مسلمان ٹھہرتے نہیں تھے بلکہ اپنے علوم
سے دنیا کو مستفیض کرتے چلے جاتے تھے.یہی خوبیاں ہیں جو جیتنے والی اقوام سے مخصوص ہیں.ہماری جماعت کو سوچنا چاہئے کہ کیا ہم میں بھی یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں یا نہیں؟
حکومت کا حصہ تو اپنے وقت پر آئے گا.لیکن سوال یہ ہے کہ کیا باقی خوبیاں ہم نے اپنے اندر
پیدا کر لی ہیں ؟ کیا ہم اپنی نظر میں لوگوں کی نظر میں اور پھر خدا تعالیٰ کی نظر میں ہر قسم کے نقائص
سے پاک ہیں؟ کیا ہمارے اخلاق اس قسم کے ہیں کہ ہم نہ اپنی زبان سے لاغیہ سنتے ہیں اور
نہ لوگوں کی زبان سے لاغیہ سُنتے ہیں؟ اور کیا ہماری کوششیں یہی ہوتی ہیں عَيْن جَارِيَةٌ کی
طرح ہم جو بات بھی سنیں اُسے دوسرے لوگوں تک پہنچا دیں یا ہم صرف واہ واہ اور سبحان اللہ
کہنے کے لئے سنتے ہیں؟ صحابہ کی یہ حالت تھی کہ وہ رات اور دن تعلیم میں لگے رہتے تھے اور
پھر جو کچھ سیکھتے اسے اپنے سینوں میں ہی نہ رکھتے بلکہ لوگوں تک پہنچا دیتے.گویا وہ ایک جاری
چشمہ تھا جو دنیا کو سیراب کر رہا تھا.کتنی زبر دست خواہش دوسروں تک علوم پہنچانے کی ہے جو
اُس صحابی کے دل میں پائی جاتی تھی جس نے کہا کہ اگر تلوار میری گردن پر چل رہی ہو تو اُس
وقت میری آخری خواہش یہ ہوگی کہ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بات بیان کرنی
مجھ سے رہ گئی ہو تو میں اُسے جلدی جلدی بیان کر دوں.یہی خوبی ہماری جماعت کو اپنے اندر پیدا
کرنی چاہئے اور اپنے آپ کو علوم کے لحاظ سے عَيْن جَارِيَةٌ ثابت کرنا چاہئے.726
Page 735
فِيْهَا سُرُ رْ مَّرْفُوعَةٌ
املا سرد سیریز کی جمع ہے اور سُٹرڈ کی بجائے آستری بھی جمع کے طور پر استعمال ہوتا
ہے.اس کے معنے تخت کے ہوتے ہیں.خصوصا یہ لفظ بادشاہ کے تخت کے لئے بولا جاتا ہے
چنا نچہ کہتے ہیں زَالَ عَن سَرِيرِہ وہ اپنے سریر سے ہٹ گیا اور مراد یہ ہوتی ہے کہ ذَهَبَ عِزة
نِعْمَتُه اُس کی عزت اور دولت جاتی رہی ستمی به لاَنَّ مَنْ جَلَسَ عَلَيْهِ مِنْ أَهْلِ الرَّفْعَةِ
وَالْجَاهِ يَكُونُ مَسْرُورًا سریر کا لفظ اس لئے استعمال کیا جاتا ہے کہ مالدار اور جاہ وجلال کے
مالک لوگ تخت پر بیٹھتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں.پس چونکہ اس مقام کا حصول دل میں سرور
پیدا کرتا ہے اس لئے تخت کا نام ہی سر پر رکھ دیا گیا (اقرب)
مَرْفُوعَةٌ رَفَعَ سے ہے اور رفعه کے معنے ہوتے ہیں اُس نے کسی چیز کو بلند کیا
(اقرب ) یہ بلندی خواہ اونچا بنانے کے لحاظ سے ہو جیسے کہتے ہیں مینار اونچا بنایا گیا اور خواہ اونچا
کرنے کے لحاظ سے ہو جیسے کسی چیز کو اُٹھا کر اونچا کیا جاتا ہے.دونوں رنگ میں اس لفظ کا
استعمال ہو جاتا ہے.مثلاً کہتے ہیں دیوار اونچی ہے اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ لمبی چلی جاتی ہے
اور قامت کے اعتبار سے بلند ہے.یا کہتے ہیں چھت اونچی ہے اور مراد یہ ہوتی ہے کہ زمین
اور چھت میں فاصلہ زیادہ ہے.گویا قامت کی بلندی ہو یا فاصلہ کی زیادتی دونوں پر رفع کا لفظ
اطلاق پاتا ہے.پس مَرْفُوعَةٌ کے معنے ہوں گے اُونچے کئے ہوئے.بلند کئے ہوئے.اس آیت کے ایک معنے یہ ہیں کہ وہ بلند شان والے ہوں گے.کیونکہ سٹرڈ کے ساتھ
مَرْفُوعَةٌ ہونا زیادہ شان اور عزت پر دلالت کرتا ہے.لیکن اس کے یہ بھی معنے ہیں کہ وہ بلند
رکھے گئے ہوں گے.گویا دونوں قسم کی خوبیاں اُن میں پائی جاتی ہوں گی.مومنوں کی یہ شان بھی ہوگی کہ وہ نیک اعمال میں ترقی کرتے جائیں گے اور دوسروں سے
نیکی میں بلند قامت ہونے کی کوشش کریں گے اور وہ اس لحاظ سے بھی مَرْفُوعَةٌ ہوں گے کہ
خُدا تعالیٰ اُن کو اپنی طرف اٹھا لے جائے گا.گویا جہاں تک اُن کا انسانوں سے واسطہ ہے وہ
727
Page 736
دوسرے بنی نوع انسان سے بلند قامت ہوں گے اور نیکی اور تقویٰ کے لحاظ سے اس قدر فائق
ہوں گے کہ اُن میں اور عام لوگوں میں کوئی نسبت ہی نہیں ہوگی.اور جہاں تک خدا تعالیٰ کا
تعلق ہے وہ باقی انسانوں کے مقابل پر اُن سے الگ قسم کا سلوک کرے گا اور وہ انہیں
اپنا مقرب بنالے گا.اس آیت میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ مسلمانوں کو جو بادشاہتیں ملیں گی وہ بالکل
الگ قسم کی ہوں گی.وہ اس جہان کی بادشاہتوں کی طرح نہیں ہوں گی بلکہ مَرْفُوعَةٌ ہوں گی.اُن کے تخت آسمان پر رکھے جائیں گے.چنانچہ دیکھ لو مسلمان بادشاہ تو ہوئے مگر انہوں نے
دنیوی طور پر بادشاہت سے کیا فائدہ اٹھایا؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تمام عالم اسلامی کے
بادشاہ تھے مگر اُن کو کیا ملتا تھا.پبلک کے روپیہ کے وہ محافظ تو تھے مگر خود اس روپیہ پر کوئی
تصرف نہیں رکھتے تھے.بے شک حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بڑے تاجر تھے مگر چونکہ ان کو
کثرت سے یہ عادت تھی کہ جو نہی روپیہ آیا خدا تعالیٰ کی راہ میں دے دیا اس لئے ایسا اتفاق
ہوا کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور آپ خلیفہ ہوئے تو اس وقت آپ کے
پاس نقد روپیہ نہیں تھا.خلافت کے دوسرے ہی دن آپ نے کپڑوں کی گٹھڑی اٹھائی اور
اسے بیچنے کے لئے چل پڑے.حضرت عمر رضی اللہ عنہ رستہ میں ملے تو پوچھا کیا کرنے لگے
ہیں؟ انہوں نے کہا آخر میں نے کچھ کھانا تو ہوا.اگر میں کپڑے نہیں بیچوں گا تو کھاؤں گا کہاں
سے.حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا.اگر آپ کپڑے بیچتے رہے تو خلافت کا کام
کون کرے گا؟ حضرت ابو بکرؓ نے جواب دیا کہ اگر میں یہ کام نہیں کروں گا تو پھر گزارہ کس
طرح ہوگا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ بیت المال سے وظیفہ لے لیں.حضرت
ابوبکر نے جواب دیا کہ میں یہ تو برداشت نہیں کر سکتا.بیت المال پر میرا کیا حق ہے.حضرت
عمر رضی اللہ عنہ نے کہا جب قرآن نے اجازت دی ہے کہ دینی کام کرنے والوں پر بھی
بیت المال کا روپیہ صرف ہو سکتا ہے تو آپ کیوں نہیں لے سکتے.چنانچہ اس کے بعد
728
Page 737
سبیت المال سے اُن کا وظیفہ مقرر ہو گیا.مگر اُس وقت کے لحاظ سے وہ وظیفہ صرف اتنا تھا جس
سے روٹی کپڑے کی ضرورت پوری ہو سکے.پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے.اُن کو بھی ہم
دیکھتے ہیں کہ بالکل سادہ طور پر اپنی زندگی بسر کرتے تھے.خلفاء میں سے صرف حضرت عثمان
رضی اللہ عنہ کے پاس دولت تھی مگر آپ چونکہ بہت تھی تھے اس لئے جو کچھ پاس ہوتا بالعوم تقسیم
کر دیا کرتے تھے.لوگ اُن پر یہ اعتراض بھی کرتے تھے کہ آپ نے فلاں کو مال دیا ہے.فلاں کو مال دیا ہے.آپ جواب دیتے کہ تم کو اس سے کیا؟ میرا اپنا روپیہ ہے میں جہاں
چاہوں خرچ کروں.تم اس میں دخل دینے والے کون ہو.تو کوئی فائدہ بھی خلفاء نے بیت المال
سے نہیں اُٹھایا بلکہ تمام کا تمام روپیہ انہوں نے لوگوں کے فائدہ کے لئے اپنی نگرانی میں صرف
کیا.غرض مسلمانوں کے تخت دوسروں کی نسبت بلند تھے.دنیا کے بادشاہ قومی خزانہ کو اپنا خزانہ
سمجھتے ہیں اور وہ اس پر پورا پورا تصرف رکھتے ہیں.آج پبلک اور بادشاہتوں میں یہی جنگ
جاری ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ تم روپیہ رعایا کے لئے خرچ کرو اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا روپیہ
ہے ہم جس طرح چاہیں گے خرچ کریں گے.پس اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اسلامی حکومت کا نقشہ کھینچا ہے اور بتایا ہے کہ اُن کے
تخت مرفوعہ ہوں گے.وہ لوگوں کے فائدہ کے لئے حکومت کریں گے.گویا نام کے بادشاہ
ہوں گے مگر حقیقتاً زمین کے بادشاہوں سے بہت بلند مقام پر ہوں گے.وہ خزانوں کو اپنے
خزانے نہیں سمجھیں گے بلکہ ملک اور قوم کی ملک تصور کریں گے.یہی اسلامی حکومت کے معنے
ہیں کہ اُس میں خزانہ کسی فرد کا نہیں ہوتا.قوم بحیثیت مجموعی اُس خزانہ کی مالک ہوتی ہے.میں نے دیکھا ہے بعض غیر احمدی جو ہماری جماعت کو بھی عام پیروں فقیروں کی جماعتوں کی
طرح سمجھتے ہیں مجھے خط لکھتے ہیں کہ آپ بڑے مالدار ہیں آپ ہمیں اتنے ہزار یا اتنے لاکھ دے
دیں.میں انہیں جواب دیتا ہوں کہ میرے پاس جو مال آتا ہے وہ میر انہیں سلسلہ کا ہوتا ہے.729
Page 738
میں اسے اپنی مرضی کے مطابق تقسیم کرنے کا حق نہیں رکھتا.غرض وہ لوگ یہ نہیں سمجھ سکتے کہ میں
بھی کسی قانون کے ماتحت ہوں اور اُس قانون کو توڑ کر بیت المال کے روپیہ کو خرچ کرنے کا
حق نہیں رکھتا.انہیں بہت سمجھایا جاتا ہے کہ مجھے خزانہ پر کلی اختیار نہیں بلکہ خدا تعالیٰ نے
مجھے بھی بعض قوانین کے ماتحت رکھا ہے مگر ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی اور وہ یہی خیال
کرتے ہیں کہ میں بخل کی وجہ سے اُن کی مدد نہیں کرتا.یہ حالت بتاتی ہے کہ مسلمان اسلامی
تعلیم سے آج کل کس قدر دور چلے گئے ہیں.یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان امراء مغضوب ہیں
جبکہ گزشتہ ایام میں مسلمان امراء اور بادشاہ نہ صرف اپنوں کے محبوب تھے بلکہ غیروں کے بھی
محبوب تھے.کیونکہ وہ حکومت کے روپیہ کو ملک اور خصوصاً غرباء کی ترقی کے لئے خرچ کرتے
تھے اور امراء بھی اپنے اموال کو ایک الہی امانت سمجھتے تھے اور اسے عیاشی پر نہیں بلکہ رفاہ عام
کے کاموں پر خرچ کرتے تھے.وَالْوَابٌ مَّوْضُوعَةٌ
اكواب : آبخوروں کو کہتے ہیں اور مَوْضُوعَةٌ، وَضَعَ سے ہے جس کے معنے رکھنے کے
ہوتے ہیں لیکن اس میں اور حظ میں فرق ہے.حظ کے معنے محض رکھنے کے ہوتے ہیں اور
وَضَعَ کے معنے مناسب طور پر رکھنے کے ہوتے ہیں.قرآن کریم میں ہے وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا
للانام (الرحمن (11) اس کے معنے یہ ہیں کہ زمین کو اس طرح بنایا کہ چار پائیوں کو اس سے
فائدہ پہنچے.اسی طرح فرما ا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ (نساء47) یعنی مناسب محل سے
بدل کر دوسری جگہ رکھ دیتے ہیں.أكواب مَوْضُوعَةٌ کے تین معنے ہو سکتے ہیں.آبخورے مومنوں کے پاس رکھے جائیں
گے.چونکہ آبخورے کا کسی کے پاس رکھنا پینے کے لئے ہوتا ہے اس لئے ان معنوں سے یہ
استنباط بھی ہوگا کہ وہ بھرے ہوئے ہوں گے.دوسرے اس کے یہ معنے ہیں کہ آبخورے اُن کے پاس ہی دھرے ہوں گے.730
Page 739
تیسرے معنے اس کے یہ ہیں کہ آبخورے چشموں کے پاس دھرے ہوں گے.اس آیت میں مسلمانوں کے قرب الہی اور ان کی سخاوت اور فیاضی کا ذکر کیا گیا ہے.آبخورے اُن کے پاس رکھے جائیں گئے کا ایک اشارہ اُن کے بھرے ہوئے ہونے کی
طرف ہے.پس اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اپنے انعامات کا جام لبالب
پلائے گا اور ہر وقت پلائے گا.اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ مومن فضل و احسان کے جام بھر کر
اپنے پاس رکھیں گے تا جو آئے اُسے پلائیں.وہ علوم آسمانی کے جام بھر بھر کر لوگوں کے سامنے
پیش کریں گے اور کہیں گے لو جی یہ آبخورے پی لو.دوسرے معنے اس سے یہ نکلتے ہیں کہ آبخورے مومنوں کے پاس ہی رکھے ہوں گے.یعنی
علوم آسمانی کا حصول ان کے لئے آسان کر دیا جائے گا.ادنی کوشش سے وہ رُوح کی پیاس
بجھا سکیں گے.تیسرے معنے اس کے یہ ہیں کہ آبخورے چشموں کے پاس دھرے ہوں گے.یعنی دعوتِ
عامہ ہوگی جو چاہے پئے.گویا:.اول.اُن کے سینوں کو علوم آسمانی سے پُر کیا جائے گا.دوم.اُن کا علم اور عرفان لوگوں کے لئے اس قدر وسیع ہوگا کہ کسی کو مانگنے کی ضرورت نہیں ہوگی.سوم.وہ آبخوروں کو بھر بھر کر رکھتے چلے جائیں گے اور لوگوں سے کہیں گے آؤ اور پی لو.چہارم.اُن کے لئے آسمانی علوم کا حصول آسان کر دیا جائے گا.پنجم.ان کے فیوض کا دروازہ ہر ایک کے لئے گھلا ہوگا جو چاہے اس سے
فائدہ اُٹھائے.وَلَمَارِقُ مَصْفُوقَةٌ
ا نمارق تموی اور موقہ کی جمع ہے اور یہ لفظ تینوں طرح آجاتا ہے.نمرق.ترقی اور
يمرى تمارق اُن چھوٹے چھوٹے تکیوں کو کہا جاتا ہے جو ٹیک لگانے کے لئے پیچھے رکھے
جاتے ہیں (اقرب) ایک گاؤ تکیہ ہوتا ہے جو متمدن ممالک میں صرف وہاں لگاتے ہیں
731
Page 740
جہاں قوم کا سردار بیٹھا ہو.لیکن تمارق اُن چھوٹے چھوٹے تکیوں کو کہتے ہیں جو دیواروں کے
ساتھ ساتھ تمام اہل مجلس کے لئے رکھے جاتے ہیں اور جو بھی آتا ہے اُس تکیے سے ٹیک لگا کر
بیٹھ جاتا ہے.اس آیت میں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ مسلمان سارے کے سارے معربا ز ہوں
گے.یہ نہیں کہ ان میں سے صرف ایک شخص کے پیچھے گاؤ تکیہ ہو اور باقی تکیوں کے بغیر ہوں.بلکہ ہر شخص کے پیچھے ایک ایک تکیہ ہوگا.یعنی اللہ تعالیٰ قوم کی قوم کو معز اور باعظمت بنادے
گا.یہ خوبی اگر کامل طور پر ملی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو.افسوس ہے
کہ ابھی ہمارے اندر بھی کئی لوگ ایسے پائے جاتے ہیں جن کو دینی علوم حاصل کرنے کا کوئی
شوق نہیں.جو قرآن کریم کے علوم سے بہت حد تک ناواقف ہیں اور جن کے دلوں میں یہ
احساس بھی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ قرآن کریم کو سمجھنے اور اس کے علوم کو سیکھنے کی کوشش کریں.یه محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی تھی جن کو ایسی با کمال جماعت ملی جس نے
آپ کی باتوں کوٹنا ، اُن پر عمل کیا اور پھر اُسے دوسرے لوگوں تک پہنچایا.اس میں کوئی شبہ
نہیں کہ ہماری جماعت میں کچھ لوگ ایسے ضرور ہیں جو صحابہ کی طرح دین کی ہر بات کو سیکھنے،
اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں.مگر وہاں سب کے
سب ایسے تھے.یہ ایک ایسی خوبی اور ایسا کمال ہے جس پر ہر قوم کو رشک کرنا چاہئے اور اپنے
آپ کو اُن جیسا بنانے کی کوشش کرنی چاہئے.اسی خوبی کا اللہ تعالیٰ نے زیر تفسیر آیت میں
ذکر کیا ہے اور بتایا ہے کہ مسلمانوں میں یہ نہیں ہوگا کہ ایک شخص گاؤ تکیہ لگا کر بیٹھا ہوا ہو اور
باقی لوگ اُس کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہوں بلکہ تمام افراد کو عزت حاصل ہوگی، تمام
افراد کو وجاہت حاصل ہوگی، تمام افراد کو عظمت حاصل ہوگی اور تکیے سب کے پیچھے ہوں گے.کسی ایک فرد کے پیچھے بڑا سا تکیہ نہیں رکھا ہوگا.732
Page 741
وَزَرَابِي مَبْثُوثَةٌ
رائی کے معنے نمارق کے بھی ہوتے ہیں اور فرش کے بھی.ذرائی کا واحد زربی بھی
ہوتا ہے اور زربية بھی (اقرب)
مَبْثُوثَةٌ بہت سے اسم مفعول کا صیغہ ہے اور بت کے معنے ہیں کسی چیز کو پھیلایا
( مفردات ) اور مَبْثُوثَةٌ کے معنے ہوں گے پھیلائے ہوئے.زَرَابِي مَبْعُوثَةٌ کے یہ معنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہر ملک میں عزت بخشے گا اور ہر
قوم کے لوگ اُن کو اپنی آنکھوں پر بٹھائیں گے.تمارِقُ مَصْفُوفَةٌ کے معنے تو یہ تھے کہ اُن
کے ہر فرد کو عزت کے مقام پر بٹھایا جائے گا یعنی ساری کی ساری قوم معرہ زہوگی.یہ نہیں ہوگا
کہ کوئی ایک فرد معز ہو اور باقی لوگ ذلیل ہوں.بلکہ ہر ایک کے پیچھے تکیہ لگا ہوا ہوگا.اب زَرَابِی مَبْثُونَةٌ میں یہ بتاتا ہے کہ اُن کی دُنیا کے کونہ کونہ اور زمین کے گوشہ گوشہ میں
عزت کی جائے گی.زربیة کے معنے جیسا کہ بتائے جاچکے ہیں فرش کے ہوتے ہیں.پس
زَرَابِي مَبْثُوثَةٌ کے یہ معنے ہوں گے کہ مسلمانوں کے لئے ہر جگہ فرش بچھے ہوئے ہوں گے.دنیا
کے ہر کونہ میں وہ معزز ہوں گے.اللہ تعالیٰ اُن کو ہر جگہ عزت دے گا اور ہر مقام پر اُن کی
وجاہت کا لوگوں پر اثر پڑے گا.یہی وجہ ہے کہ تمارق کے لئے مصفوفة کا لفظ استعمال کیا
تھا.اور ذرائی کے لئے مبحوثة کا لفظ استعمال کیا ہے.مَصْفُوفَة کے معنے ہوتے ہیں صف
میں رکھے ہوئے اور مَصْفُوفَة کہنے سے مطلب یہ تھا کہ جب مسلمان مجالس میں حاضر ہوں گے
سب کے سب عزت کے مقام پر بیٹھیں گے.ان میں سے کوئی ذلیل نہ ہوگا.لیکن ڈرائی میں
کسی خاص مجلس کا ذکر نہیں بلکہ عام ذکر ہے اور بتایا گیا ہے کہ وہ جہاں جائیں گے لوگ اُن کے
رستہ میں فرش بچھائیں گے.اُن کا استقبال کریں گے.اُن سے عزت کے ساتھ پیش آئیں گے
اور چاہیں گے کہ وہ اُن کے گھروں میں رہیں اور اس طرح اُن کے لئے برکت کا باعث بنیں.لوگ عموما ظاہر پر مرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ استقبال وہی ہوتا ہے جب بڑی بڑی قالینیں
733
Page 742
بچھائی جائیں، شاندار دروازے بنائے جائیں، رنگ برنگ کی جھنڈیاں لگائی جائیں اور
ظاہری لحاظ سے نمائش کی جائے حالانکہ اصل استقبال قالین بچھانا نہیں بلکہ آنکھوں کا فرش راہ
کرنا ہے.ایک شاعر نے کہا ہے.ع
حضرت واعظ جو آئیں دیدہ و دل فرش راہ
پس لوگوں کے دیدہ و دل کا فرش راہ ہونا ہی اصل عزت کی علامت ہے اور اسی کی طرف
زرَابِيُّ مَبْعُوثَةٌ میں اشارہ کیا گیا ہے اس سے مراد ظاہری ذرا بچ نہیں.ان ظاہری زرائی کی تو
صحابہ کو پرواہ بھی نہیں تھی.غرض بتایا کہ مسلمان جہاں جائیں گے لوگ اپنی آنکھیں فرش راہ کریں گے اور کہیں گے
آئیے اور تشریف رکھئے.آخر وہ کون سی چیز تھی جس کی وجہ سے اسلام کو فتح حاصل ہوئی اور
مسلمان جہاں گئے پھیلتے چلے گئے.اس کی وجہ یہی تھی کہ مسلمان منصف مزاج تھے اور وہ لوگوں
کے حقوق کو غصب نہیں کرتے تھے.غصہ سے انسان تب لڑتا ہے جب وہ سمجھتا ہے کہ میرا
نقصان ہو رہا ہے لیکن جب وہ سمجھتا ہو کہ ہمارے اپنے بادشاہ ظلم کرتے ہیں مسلمان آئے تو
انصاف کریں گے اُس وقت وہ دل سے نہیں لڑسکتا بلکہ عزت کے ساتھ پیش آتا ہے.پس
فرماتا ہے کہ مسلمانوں کی حالت یہ ہوگی کہ وہ جدھر جائیں گے لوگ اپنی آنکھیں اُن کی راہ میں
بچھائیں گے.جس جگہ ٹھہریں گے لوگ تکیے لگائیں گے.اُن کے قدموں میں قالینیں
بچھائیں گے جیسے گورنروں یا حاکموں کے استقبال کے موقع پر ہوتا ہے اور کہیں گے کہ ہمارے
ہاں ہی ٹھہرئیے اور آگے نہ جائیے.أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ
ابل کے معنے اونٹوں کے ہوتے ہیں لیکن بعض علماء ادب نے اس کے معنے بادل کے
بھی کئے ہیں.امام راغب نے اپنی کتاب مفردات میں لکھا ہے کہ اس کے معنے اگر بادل
کے ہیں تو بھی استعارہ کے طور پر ہیں.لغت میں یہ معنے نہیں ہیں.گو بعض آئمہ نے حتٰی کہ
734
Page 743
کسائی تک نے کہا ہے کہ اس کے معنے بادل کے ہیں.جیسا کہ صاحب محیط کہتے ہیں
وَرُوِيَتْ عَنْ أَبِي عَمْرٍو وَأَبِي جَعْفَرٍ وَالْكَسَائِي وَقَالُوا إِنَّهَا السَّحَابُ عَنْ قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ
اللغة - لیکن لغت کی کتب لکھنے والوں نے اِن معنوں کو تسلیم نہیں کیا.وہ یہی کہتے ہیں کہ لغت
کے لحاظ سے اس کے حقیقی معنے اونٹوں کے ہی ہیں.میں بھی پہلے اس آیت میں اہل کے معنے
اونٹوں کی بجائے بادل کے کیا کرتا تھا اور سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اگر اہل کے معنے یہاں اونٹوں
کے ہی کئے جائیں تو پھر اہل اور سماء میں جوڑ کیا ہوا.اُس وقت بادل کے معنے زیادہ قرین
قیاس معلوم ہوتے تھے.لیکن اب جو میں نے غور کیا تو یہی بات ٹھیک نکلی کہ اس آیت میں
اہل کے معنے اونٹوں کے ہی ہیں.پہلے میں اس آیت پر صرف اسی آیت کو سامنے رکھ کر غور کرتا
رہا ہوں.لیکن اب جو میں نے ترتیب آیات کے لحاظ سے غور کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ اونٹوں کا
سماء کے ساتھ تو جوڑ نظر آتا ہے مگر بادل کا کوئی جوڑ نہیں.جیسا کہ مفردات والوں اور صاحب
کشاف نے لکھا ہے یہ درست معلوم ہوتا ہے کہ اہل کے معنے جن لوگوں نے بادل کے کئے
ہیں فَعَلى تَشْبِيْهِ السَّحَابِ یعنی وہ اس وجہ سے کئے ہیں کہ اونٹ اس طرح اونچے نیچے چلتے
ہیں جس طرح بادل چلتا ہے.پس چونکہ اہل کو چلنے کے لحاظ سے بادلوں سے مشابہت ہوتی
ہے اس لئے محاورہ میں اہل کا لفظ بادل کے لئے استعمال کیا جانے لگاور نہ ابل کے اصل معنے
بادل کے نہیں ہیں.أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ میں مضمون نیچے
سے اوپر گیا ہے.اور اگلی آیت یعنی وَاِلَی الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ
سطحت میں مضمون اوپر سے نیچے آیا ہے.اس سے صاف پتہ لگتا ہے کہ یہاں دو الگ الگ
مضمون بیان ہوئے ہیں.ایک مضمون میں نیچے سے اوپر کی طرف توجہ دلائی گئی ہے اور
دوسرے مضمون میں اوپر سے نیچے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے.اگر ان آیات میں دو الگ الگ
مضمون تسلیم نہ کئے جائیں تو پھر اہل ، سماء.جبال اور ارض میں کوئی بھی ترتیب نظر نہیں آتی.735
Page 744
ترتیب کے لحاظ سے مدارج دو ہی طرح بیان کئے جاسکتے ہیں.یا نیچے سے اوپر کی طرف
مضمون کو لے جایا جائے یا اوپر سے نیچے کی طرف.اب اس آیت میں پہلے اونٹوں کا ذکر ہے
پھر سماء کا.یہاں تک تو ترتیب درست ہے.یعنی نیچے سے اوپر کی طرف مضمون لے جایا گیا
ہے مگر اس کے بعد پہاڑوں کا ذکر ہے جو نہ سماء سے اونچے ہیں نہ اُن کے برابر.اور اس کے
بعد زمین کا ذکر ہے جو پہاڑوں سے اونچی نہیں ہوتی.دوسری ترتیب یہ ہوتی ہے کہ اوپر سے نیچے کی طرف آیا جائے.مگر اس لحاظ سے بھی بات
نہیں بنتی کیونکہ اونٹ جو چھوٹی چیز ہے اُسے پہلے ذکر کر دیا گیا ہے اور سماء جو بلند چیز ہے اُس کا
بعد میں ذکر کیا گیا ہے.گویا نہ یہ ترتیب بنتی ہے کہ اونٹ سب سے نیچا ہو.اُس سے اُونچا
آسمان ہو.اس سے اونچا پہاڑ ہو اور اس سے اونچی زمین ہو.اور نہ یہ ترتیب بنتی ہے کہ اونٹ سب
سے اونچا ہے.آسمان اُس سے نیچا ہو.پہاڑ اس سے نیچے ہوں اور زمین اُن سے نیچی ہو.کبھی کبھی ایک اور رنگ بھی ترتیب کے بیان میں استعمال کر لیا جاتا ہے وہ اس طرح کہ
پہلے درمیانی چیز کا ذکر کر دیا جاتا ہے پھر اُن اشیاء کا ذکر کر دیا جاتا ہے جو اس کے دائیں بائیں
ہوں.مگر یہاں اہلی کے بعد آسمان کا ذکر دیا گیا ہے.آسمان کے بعد پہاڑوں کا اور پہاڑوں
کے بعد زمین کا.اگر چوٹی کی چیز کو پہلے بیان کر دیا جاتا اور اس کے بعد ایسی چیز کا نام لیا جاتا جو
اس سے کم اونچی ہیں تو خیر کوئی بات بھی تھی مگر بظاہر اس جگہ کوئی اصل بھی مڈ نظر نہیں رکھا گیا.نہ
نیچے سے اوپر مضمون گیا ہے نہ اوپر سے نیچے کو مضمون گیا ہے اور نہ درمیان کی کسی چیز کا پہلے
ذکر کر کے اس سے تعلق رکھنے والی چیزوں کا بعد میں ذکر کیا گیا ہے.پس یا تو ان آیات کو
بے ترتیب قرار دینا پڑے گا جو قرآن کریم کی شان کے خلاف ہے.یا ان آیات کو دو الگ
الگ مثالوں پر مشتمل قرار دینا ہوگا.جن میں سے ایک میں نیچے سے اوپر کی طرف مضمون لے
جایا گیا ہے اور دوسری میں اوپر سے نیچے کی طرف ایک مثال کے ذریعہ اہل اور سماء کی آپس
میں کوئی نسبت بتائی ہے.اور دوسری مثال کے ذریعہ جبال اور آرض کی آپس میں کوئی
736
Page 745
نسبت بتائی ہے.اور میرے نزدیک ان آیات میں یہی آخری طریق استعمال ہوا ہے.ابل
کے معنے اس جگہ اونٹوں ہی کے ہیں لیکن سماء کے معنے اس جگہ آسمان کے نہیں بلکہ بادل کے
ہیں جیسا کہ وَالسَّمَاء ذَاتِ الرّجع (الطارق) میں سماء کے معنے بادل کے ہیں.آیت میں کفار کو اونٹوں سے مشابہت دی ہے کہ باوجود اونچا ہونے کے سواری کے
کام آتے ہیں اور مسلمانوں کو بادلوں سے مشابہت دی ہے کہ نظر نہ آنے والے ذروں سے بنتا
ہے اور آخر بلند ہو کر دنیا پر چھا جاتا اور اُسے سیراب کر دیتا ہے.وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتُ
اس آیت میں دوسری مثال بیان کی گئی ہے جس کا مضمون اوپر سے نیچے کی طرف آتا
ہے.فرماتا ہے تم پہاڑوں کو دیکھو کہ وہ کس طرح زمین میں گڑے ہوئے ہیں.دوسری جگہ
پہاڑوں کا فائدہ اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے کہ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ
تميدرهم (الانبیاء 32) ہم نے پہاڑ اس لئے بنائے ہیں کہ زمین ہل نہ جائے اور لوگ تباہ
نہ ہو جائیں.زمین کی غیر ضروری حرکت کو پہاڑوں نے ہی روکا ہوا ہے ورنہ بنی نوع انسان کا
زمین میں قیام بالکل ناممکن ہو جاتا.اللہ تعالی گزشتہ مضمون کے تسلسل میں کفار کو توجہ دلاتا ہے
کہ تم اپنے دلوں میں خیال کرتے ہو کہ یہ کیونکر ہوسکتا ہے کہ مسلمان غالب آجائیں.اور ہم
مغلوب ہو جائیں.ہم طاقتور اور بڑی عزت اور شان رکھنے والے ہیں.یہ کس طرح ہوسکتا ہے
کہ ہمارے ہم قوم اور ہمارے ہم مذہب ہم کو چھوڑ کر ان کے پیچھے دوڑنے لگ جائیں.مگر
تمہارا یہ خیال بالکل بے بنیاد ہے.تم بے شک اچھے ہو مگر تمہاری اور مسلمانوں کی حالت میں
جو کچھ فرق ہے وہ اس سے ظاہر ہے کہ مسلمانوں کو ہم نے اپنی مشیت کے ماتحت پہاڑ بنایا
ہے اور تم کو زمین بنایا ہے.زمین پہاڑوں کے ذریعہ ہی قائم رہتی ہے.اگر پہاڑ نہ ہوں تو
زمین بھی اس حالت میں نہ رہے.پس بے شک تم میں خوبیاں ہیں اس سے ہم انکار نہیں
کرتے.جس طرح زمین میں بھی خوبیاں پائی جاتی ہیں اور کوئی شخص ان خوبیوں سے انکار نہیں
737
Page 746
کرسکتا مگر زمین یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ اُسے پہاڑوں کی ضرورت نہیں یا پہاڑوں کے بغیر بھی اُس
کی زندگی قائم رہ سکتی ہے.زمین کی زندگی پہاڑوں کے بغیر قطعی طور پر ناممکن ہے.اسی طرح
اب جبکہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ بنا دیا ہے تمہارا فائدہ اسی میں ہے کہ زمین کی طرح اُن
کے مقابلہ میں پچھ جاؤ.جس طرح زمین پہاڑ کے مقابلہ میں بچھ کر ہی فائدہ اٹھاتی ہے اس کے
بغیر نہیں اسی طرح تمہارا فائدہ بھی اسی میں ہے کہ تم مسلمانوں کے مقابلہ میں کھڑے نہ ہو.اگر پہاڑ کی اونچائی کے لحاظ سے اس مثال کو مسلمانوں پر چسپاں کیا جائے تو پھر معنے یہ ہوں
گے کہ مسلمانوں کی مثال پہاڑوں کی طرح ہے اور تمہاری مثال زمین کی طرح.ان مسلمانوں
کے ذریعہ ہی اب دنیا سے فتنہ و فساد ڈور ہوں گے.بے شک زمین سرسبز و شاداب ہوتی ہے
اور کئی قسم کی روئید گیاں اس میں پیدا ہوتی ہیں مگر انہی پہاڑوں کے ذریعہ.کیونکہ وہی بادلوں
کے برسنے کا ذریعہ بنتے ہیں اور وہی دریاؤں کا منبع ہیں.پس اب تمہاری ترقی مسلمانوں کے
ساتھ وابستہ ہے.ان سے جُدا ہو کر تم سکھ نہیں پاسکتے.لَسْتَ عَلَيْهِمْ مُصَيْطِرٍ
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مُصیطر نہ ہونا دونوں لحاظ سے ہے.مومنوں کے لحاظ
سے بھی اور کافروں کے لحاظ سے بھی.یعنی آپ نہ مومنوں کے لئے مُصيطر ہیں اور نہ کفار کے
لئے مُصيطر ہیں.کفار کو اگر جبر آمذہب میں شامل بھی کیا جائے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو
سکتا.وہ ظاہر میں تو مذہب قبول کرلیں گے لیکن دل میں منافق رہیں گے.اس لئے اللہ تعالیٰ
نے لَسْتَ عَلَيْهِمُ بمُصَيْطِرِ کہہ کر غیر مذاہب والوں کو جبراً اسلام میں شامل کرنے کی
ممانعت فرما دی ہے اور بتایا ہے کہ ہم نے تمہیں اُن
کا داروغہ مقرر نہیں کیا.اگر تم جبر سے کام
لو گے تو اس سے نہ مومن کو فائدہ ہوگا نہ کافر کو.کافر کو تو اس لحاظ سے فائدہ نہیں ہوگا کہ اگر وہ
تلوار کے ڈر سے مسلمان ہو بھی جائے تو بہر حال وہ منافق مسلمان ہو گا اور منافق کافر سے بدتر
ہوتا ہے.مومنوں کو اس لئے فائدہ نہ ہوگا کہ منافق اُن کی طاقت کو کمزور کرنے والے ہوں
738
Page 747
گے، بڑھانے والے نہیں.مومنوں پر مُصيطر اس لئے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا ایسے ہی اعمال کے نتیجہ میں انسان کو
حاصل ہوسکتی ہے جو دلی شوق اور رغبت سے کئے جائیں.جس شخص کے دل میں ذاتی طور پر
خدا تعالیٰ کی محبت کا کوئی جوش نہیں، اُس کے احکام پر عمل کرنے کا ولولہ اس کے سینہ میں نہیں
پایا جاتا، وہ معرفت اور اخلاص کی راہوں سے بیگانہ ہے.وہ اگر جبر کے ماتحت کوئی نیک
کام کرے گا بھی تو اُس کی رُوح کو پاکیزگی حاصل نہیں ہوگی اور خدا تعالیٰ کے حضور اس کے وہ
اعمال قبولیت کی نگاہ سے نہیں دیکھے جائیں گے.اس لئے فرمایا کہ تمہیں لوگوں کا مصیطر بنا کر
نہیں بھیجا گیا.جو شخص کفر کرے اور باوجود سمجھانے کے اپنے بد اعمال سے باز نہ آئے اُسے
ہمارے سپرد کر دو.تمہارے جبر سے کوئی فائدہ نہیں ہو گا.اور جو مسلمان ہے اُسے شوق اور
رغبت کے ذریعہ سے نیکی میں بڑھاؤ تا کہ اُسے ایمان کا نفع حاصل ہو.یہاں بھی دیکھ لو اسلام اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلبہ کی کیسے کھلے لفظوں میں پیشگوئی
کی گئی ہے.منگی زندگی میں جبکہ اسلام کا ابتدا تھا اور کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں آسکتا تھا
کہ اسلام بہت بڑی طاقت حاصل کر لے گا یہاں تک کہ کفار کی گردنیں مسلمانوں کے قبضہ
میں ہوں گی اور وہ اختیار رکھتے ہوں گے کہ اُن سے جو سلوک چاہیں کریں.اللہ تعالیٰ نے فرما
دیا کہ کشت عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرِ یہ صاف بات ہے کہ مکہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
کوئی ایسی طاقت حاصل نہیں تھی کہ آپ کو یہ کہا جاتا کہ تجھے ہم نے مصیطر بنا کر نہیں بھیجا.یہ
آئندہ کے متعلق پیشگوئی کی گئی تھی اور اسلام کے غلبہ کی خبر دی گئی تھی ورنہ وہ لوگ جن کو مکہ میں
گھلے بندوں نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہیں تھی اُن کو یہ کہنا کہ تمہیں زبر دستی کسی کو مسلمان
بنانے کی اجازت نہیں ایک مضحکہ خیز بات ہو جاتی ہے.یہ فقرہ صاف بتا رہا تھا کہ وہ دن
آنے والا ہے جب کہ مسلمانوں کو اتنی طاقت حاصل ہو جائے گی کہ وہ اگر چاہیں تو زبردستی
لوگوں کو مسلمان بنا سکیں گے مگر پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے بطور نصیحت فرما دیا کہ تم ایسا نہ کرنا.739
Page 748
غرض لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرِ إِلَّا مَنْ تَوَلَّی وَ كَفَرَ میں غلبہ اسلام کی پیشگوئی پائی جاتی
ہے.اور یہ بات ایسی ہے کہ عیسائی مصنفین کو بھی کھٹکی ہے.چنانچہ ویر کی اس آیت کے
ماتحت لکھتا ہے آپ کے دل میں شروع سے ہی حکومت کے خیالات اُٹھ رہے تھے.چنانچہ
ابتدائی زمانہ میں ہی اس قسم کی آیات مکہ والوں کو سُنانا بتا رہا ہے کہ انہوں نے شروع سے ہی
حکومت کا نقشہ اپنے ذہن میں جمایا ہوا تھا اور ویسے ہی خیالات دل میں پیدا ہوتے رہتے
تھے.مگر سوال یہ ہے کہ حکومت کے خیالات آخر کسی وجہ سے پیدا ہوا کرتے ہیں بغیر کسی وجہ
کے پیدا نہیں ہو سکتے.وہ شخص جو ماریں کھا رہا ہو، جولوگوں کے ظلم وستم کا نشانہ بنا ہوا ہو، جو اتنی
طاقت بھی نہ رکھتا ہو کہ باہر نکل کر خدا تعالیٰ کی عبادت کر سکے اُس کے دل میں حکومت کے
خیالات پیدا ہی کس طرح ہو سکتے ہیں اور پھر خود ساختہ خیالات پورے کس طرح ہو گئے.در حقیقت یہ ایک پیشگوئی تھی اور اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ گو اس وقت تمہاری کوئی حیثیت
نہیں مگر ایک زمانہ میں تم کو ایسا غلبہ حاصل ہونے والا ہے کہ تم جو چاہو گے کرسکو گے مگر دیکھنا
جب تمہیں غلبہ میسر آئے اُس وقت اِن لوگوں پر جبر نہ کرنا بلکہ ان کو اپنے حال پر چھوڑ دینا جو
شخص ایمان لے آئے اُسے اپنے اندر شامل کر لینا اور جو توئی اور کفر کرے اس کی پرواہ نہ کرنا.إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَ كَفَرَ
توئی اور کفر کرنے والوں کو بہت بڑا عذاب دیے جانے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے
ایک بڑی ہدایت کا انکار کیا.سزا ہمیشہ جرم کے مطابق دی جاتی ہے.معمولی قصور ہو تو معمولی
سزادی جاتی ہے اور زیادہ قصور ہو تو زیادہ سزا دی جاتی ہے.ان کا جرم چونکہ معمولی نہیں ہوگا اس
لئے انہیں سزا بھی غیر معمولی دی جائے گی کیونکہ انہوں نے اُس رسول کا انکار کیا جو تمام رسولوں
سے بڑا ہے اور جس کی شریعت تمام شریعتوں سے بڑی تھی.إِنَّ الَيْنَا اِيَابَهُمْ ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم
اس آیت سے اس مضمون کو ختم کیا گیا ہے جو سورۃ الاعلیٰ سے شروع کیا گیا تھا اور بتایا
740
Page 749
گیا ہے کہ مومن و کافر اپنے اپنے کام پورے کر کے مومن تسبیح کو بلند کر کے اور کافر کفر کی
اشاعت کر کے آخر اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور دنیوی نتائج دیکھ کر اُخروی نتائج
دیکھنے کے لئے خدا تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہوں گے.ا سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ دونوں کے متعلق یہ امر بتایا جا چکا ہے کہ ان کا آپس میں گہرا
ربط ہے.اس کا ایک ثبوت اس امر سے بھی ملتا ہے کہ احادیث میں آتا ہے رسول کریم
صلی اللہ علیہ وسلم جب سَبِّحِ اسْمَ رَبك الأعلى پڑھتے تو فرماتے سُبحان ربي الأعلی اور جب
سورۃ الغاشیہ کی تلاوت کرتے کرتے اِنَّ الَيْنَا ايَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم پر پہنچتے تو
فرماتے اللهُمَّ حَاسِبْنِی حِسَابًا يَسِيرًا.ایک سورۃ کے شروع میں ایک فقرہ کا دُہرانا اور
دوسری سورۃ کے آخر میں دوسرے فقرے کا دہرانا صاف طور پر بتا رہا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ
علیہ وسلم کے نزدیک یہ دونوں سورتیں مضمون کے اعتبار سے آپس میں جوڑ رکھتی ہیں.اسی لئے
ایک سورۃ کی ابتدا میں اور دوسری سورۃ کے انتہا میں ایک ایک فقرہ یہ بتانے کے لئے
ڈ ہراتے کہ جو مضمون سبح اسم ربك الأعلى سے شروع ہوا تھا وہ إِنَّا إِلَيْنَا ايَاتِهُمْ ثُمَّانٌ
عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ پر آکر ختم ہو گیا ہے.(ماخوذ از تفسیر کبیرزیر سورة الغاشیه)
741
Page 751
(XXXXXXX
بسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَالشَّمْسِ وَضُحُهَان
وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَهَا
وَالنَّهَارِ إِذَا جَلْهَانُ
وَالَّيْلِ إِذَا يَغْشَهَانٌ
وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنُهَان
وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَهَان
وَنَفْسٍ وَمَا سَوبَهَاتٌ
فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقُوبَهَاةٌ
قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكْهَان
سورة الشمس
1 - (میں) اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا
( اور ) بار بار رحم کرنے والا ہے (پڑھتا ہوں)
2.میں سورج کو شہادت کے طور پر پیش کرتا ہوں
اور ضحی کے وقت کو جب وہ طلوع ہونے کے بعد
اونچا ہو جاتا ہے.3.اور چاند کو جب وہ سورج کے پیچھے آتا ہے.4.اور دن کو ( بھی شہادت کے طور پر پیش کرتا ہوں )
جب وہ اس ( سورج ) کو ظاہر کر دیتا ہے.5.اور رات کو بھی ( شہادت کے طور پر پیش کرتا
ہوں ) جب وہ اس ( سورج ) کی روشنی کو آنکھوں
سے اوجھل کر دیتی ہے.6.اور آسمان کو اور اس کے بنائے جانے کو بھی.7.اور زمین کو بھی اور اس کے بچھائے جانے کو بھی
شہادت کے طور پر پیش کرتا ہوں ).اور انسانی نفس کو بھی اور اس کے بے عیب بنائے
جانے کو بھی ( شہادت کے طور پر پیش کرتا ہوں )
و.کہ اس (اللہ ) نے نفس پر اس کی بدکاری ( کی
راہوں کو بھی ) اور اس کے تقویٰ (کے راستوں) کو
بھی اچھی طرح کھول دیا ہے.10.پس جس نے اس (نفس) کو پاک کیا وہ تو
(سمجھو کہ) اپنے مقصود کو پا گیا.743
Page 752
وَقَدْ خَابَ مَنْ دَشْهَاتٌ
كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغُوبِهَا
إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَهَاتٌ
11.اور جس نے اسے (مٹی میں) گاڑ دیا ( سمجھ لو کہ) وہ
نامراد ہو گیا.12.ثمود نے اپنی حد سے بڑھی ہوئی سرکشی کی وجہ
ے ( زمانہ کے نبی کو ) جھٹلایا.13.اس وقت جبکہ اس کی قوم میں سے سب سے
بڑا بد بخت اس ( زمانہ کے نبی) کی مخالفت کے
لئے کھڑا ہوا.فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ نَاقَةَ اللهِ 14.اس پر ان (یعنی شمود کی قوم) کو اللہ کے رسول
وسميها
(صالح) نے کہا کہ اللہ کے لئے وقف شدہ اونٹنی سے
بچتے رہو اور اسی طرح اس کے پانی پلانے کے معاملہ میں
بھی ہر قسم کی سرکشی سے باز آؤ.فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ 15.لیکن انہوں نے اس (نبی) کی بات نہ مانی بلکہ
رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوْبَهَان
وَلَا يَخَافُ عُقْبُهَان
اس کو جھٹلا دیا اور (وہ) اونٹنی ( جس سے بچتے رہنے کا
انہیں حکم دیا گیا تھا اس) کی کونچیں کاٹ دیں جس کی
وجہ سے اللہ نے ان کو خاک میں ملانے کا فیصلہ کر دیا
اور ایسی تدبیریں کیں کہ اسی طرح ہو بھی گیا.16.اور وہ (اسی طرح) ان (مکہ والوں) کے
انجام کی بھی پروا نہیں کرے گا.744
Page 753
حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں:
قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی اور قسم ہے چاند کی جب پیروی کرے سورج کی.یعنی سورج سے نور حاصل کرے اور پھر سورج کی طرح اس نور کو دوسروں تک پہنچا دے.اور
قسم ہے دن کی جب سورج کی صفائی دکھاوے اور راہوں کو نمایاں کرے.اور قسم ہے رات کی
جب اندھیرا کرے اور اپنے پردہ تاریکی میں سب کو لے لے.اور قسم ہے آسمان کی اور اس
علت غائی کی جو آسمان کی اس بناء کا موجب ہوئی اور قسم ہے زمین کی اور اس علت غائی کی جو
زمین کے اس قسم کے فرش کا موجب ہوئی اور قسم ہے نفس کی اور نفس کے اس کمال کی جس نے
ان سب چیزوں کے ساتھ اس کو برابر کر دیا.یعنی وہ کمالات جو متفرق طور پر ان چیزوں میں
پائے جاتے ہیں کامل انسان کا نفس ان سب کو اپنے اندر جمع رکھتا ہے اور جیسے یہ تمام چیزیں
علیحدہ علیحدہ نوع انسان کی خدمت کر رہی ہیں، کامل انسان ان تمام خدمات کو اکیلا بجا لاتا
ہے....اور پھر فرماتا ہے کہ وہ شخص نجات پا گیا اور موت سے بچ گیا جس نے اس طرح پر نفس کو
پاک کیا.یعنی سورج اور چاند اور زمین وغیرہ کی طرح خدا میں محو ہو کر خلق اللہ کا خادم بنا.یادر ہے کہ حیات سے مراد حیات جاودانی ہے جو آئندہ کامل انسان کو حاصل ہوگی.یہ اس
بات کی طرف اشارہ ہے کہ عملی شریعت کا پھل آئندہ زندگی میں حیات جاودانی ہے جو خدا کے
دیدار کی غذا سے ہمیشہ قائم رہے گی.اور پھر فرمایا کہ وہ شخص ہلاک ہو گیا اور زندگی سے نا امید ہو گیا جس نے اپنے نفس کو خاک
میں ملا دیا اور جن کمالات کی اس کو استعدادیں دی گئی تھیں ان کمالات کو حاصل نہ کیا اور گندی
زندگی بسر کر کے واپس گیا.745
Page 754
اور پھر مثال کے طور پر فرمایا کہ ثمود کا قصہ اس بدبخت کے قصہ سے مشابہ ہے.انہوں
نے اس
اونٹنی کو زخمی کیا جو خدا کی اونٹنی کہلاتی تھی اور اپنے چشمہ سے پانی پینے سے اس کو روکا.سو
اس شخص نے در حقیقت خدا کی اونٹنی کو زخمی کیا اور اس کو اس چشمہ سے محروم رکھا.یہ اس بات کی
طرف اشارہ ہے کہ انسان کا نفس خدا کی اونٹنی ہے جس پر وہ سوار ہوتا ہے.یعنی انسان کا دل الہی
تجلیات کی جگہ ہے اور اس اونٹنی کا پانی خدا کی محبت اور معرفت ہے جس سے وہ جیتی ہے.اور
پھر فرمایا کہ ثمود نے جب اونٹنی کو زخمی کیا اور اس کو اس کے پانی سے روکا تو ان پر عذاب نازل
ہوا.اور خدا تعالیٰ نے اس بات کی کچھ بھی پرواہ نہ کی کہ ان کے مرنے کے بعد ان کے بچوں
اور بیواؤں کا کیا حال ہوگا.سو ایسا ہی جو شخص اس اونٹنی یعنی نفس کو زخمی کرتا ہے اور اس کو کمال
تک پہنچانا نہیں چاہتا اور پانی پینے سے روکتا ہے وہ بھی بلاک ہوگا.اس جگہ یہ بھی یادر ہے کہ خدا کا سورج اور چاند وغیرہ کی قسم کھانا ایک نہایت دقیق حکمت پر
مشتمل ہے جس سے ہمارے اکثر مخالف ناواقف ہونے کی وجہ سے اعتراض کر بیٹھتے ہیں کہ خدا
کو قسموں کی کیا ضرورت پڑی اور اس نے مخلوق کی کیوں قسمیں کھائیں؟
لیکن چونکہ ان
کی سمجھ زمینی ہے ، نہ آسمانی اس لئے وہ معارف حقہ کوسمجھ نہیں سکتے.سو واضح ہو کہ قسم کھانے سے اصل مدعا یہ ہوتا ہے کہ قسم کھانے والا اپنے دعوے کے لئے
ایک گواہی پیش کرنا چاہتا ہے کیونکہ جس کے دعوے پر اور کوئی گواہ نہیں ہوتا وہ بجائے گواہ
کے خدا تعالیٰ کی قسم کھاتا ہے اس لئے کہ خدا عالم الغیب ہے اور ہر ایک مقدمہ میں وہ پہلا گواہ
ہے.گویا وہ خدا کی گواہی اس طرح پیش کرتا ہے کہ اگر خدا تعالیٰ اس قسم کے بعد خاموش رہا
اور اس پر عذاب نازل نہ کیا تو گویا اس نے اس شخص کے بیان پر گواہوں کی طرح مہر لگادی.اس لئے مخلوق کو نہیں چاہئے کہ دوسری مخلوق کی قسم کھاوے.کیونکہ مخلوق عالم الغیب نہیں اور نہ
جھوٹی قسم پر سزا دینے پر قادر ہے.مگر خدا کی قسم ان آیات میں ان معنوں سے نہیں جیسا کہ
مخلوق کی قسم میں مراد لی جاتی ہے بلکہ اس میں یہ سنت اللہ ہے کہ خدا کے دو قسم کے کام ہیں،
ایک بدیہی جو سب کی سمجھ میں آسکتے ہیں اور ان میں کسی کو اختلاف نہیں اور دوسرے وہ کام جو
746
Page 755
نظری ہیں جن میں دنیا غلطیاں کھاتی ہے اور باہم اختلاف رکھتی ہے سو خدا تعالیٰ نے چاہا کہ
بدیہی کاموں کی شہادت سے نظری کاموں کولوگوں کی نظر میں ثابت کرے.پس یہ تو ظاہر ہے کہ سورج اور چاند اور دن اور رات اور آسمان اور زمین میں وہ خواص
در حقیقت پائے جاتے ہیں جن کو ہم ذکر کر چکے ہیں.مگر جو اس قسم کے خواص انسان کے نفس
ناطقہ میں موجود ہیں ان سے ہر ایک شخص آگاہ نہیں.سوخدا نے اپنے بدیہی کاموں کو نظری
کاموں کے کھولنے کے لئے بطور گواہ کے پیش کیا ہے.گویاوہ فرماتا ہے کہ اگر تم ان خواص
سے شک میں ہو جو نفس ناطقہ انسانی میں پائے جاتے ہیں تو چاند اور سورج وغیرہ میں غور کرو کہ
ان میں بدیہی طور پر یہ خواص موجود ہیں اور تم جانتے ہو کہ انسان ایک عالم صغیر ہے جس کے
نفس میں تمام عالم کا نقشہ اجمالی طور پر مرکوز ہے.پھر جب کہ یہ ثابت ہے کہ عالم کبیر کے
بڑے بڑے اجرام یہ خواص اپنے اندر رکھتے ہیں اور اسی طرح پر مخلوقات کو فیض پہنچا رہے ہیں تو
انسان جوان سب سے بڑا کہلاتا ہے اور بڑے درجہ کا پیدا کیا گیا ہے وہ کیونکر ان خواص سے
خالی اور بے نصیب ہوگا.نہیں بلکہ اس میں بھی سورج کی طرح ایک علمی اور عقلی روشنی ہے جس
کے ذریعہ سے وہ تمام دنیا کو منور کر سکتا ہے اور چاند کی طرح وہ حضرت اعلی سے کشف اور الہام
اور وحی کا نور پاتا ہے اور دوسروں تک جنہوں نے انسانی کمال ابھی تک حاصل نہیں کیا اس نور
کو پہنچا تا ہے.پھر کیونکر کہہ سکتے ہیں کہ نبوت باطل ہے اور تمام رسالتیں اور شریعتیں اور
کتابیں انسان کی مکاری اور خود غرضی ہے.یہ بھی دیکھتے ہو کہ کیونکر دن کے روشن ہونے سے
تمام راہیں روشن ہو جاتی ہیں.تمام نشیب و فراز نظر آ جاتے ہیں.سو کامل انسان روحانی روشنی کا
دن ہے.اس کے چڑھنے سے ہر ایک راہ نمایاں ہو جاتی ہے، وہ سچی راہ کو دکھلا دیتا ہے کہ
کہاں اور کدھر ہے کیونکہ راستی اور سچائی کا وہی روز روشن ہے.ایسا ہی یہ بھی مشاہدہ کر رہے ہو
کہ رات کیسی تھکوں ماندوں کو جگہ دیتی ہے.تمام دن کے شکستہ کوفتہ مزدور رات کے
کنارِ عاطفت میں بخوشی سوتے ہیں اور محنتوں سے آرام پاتے ہیں اور رات ہر ایک کے لئے
پردہ پوش بھی ہے.ایسا ہی خدا کے کامل بندے دنیا کو آرام دینے کے لئے آتے ہیں.خدا
747
Page 756
سے وحی اور الہام پانے والے تمام عقلمندوں کو جانکاہی سے آرام دیتے ہیں.ان کے طفیل سے
بڑے بڑے معارف آسانی کے ساتھ حل ہو جاتے ہیں.ایسا ہی خدا کی وحی انسانی عقل کی پردہ
پوشی کرتی ہے جیسا کہ رات پردہ پوشی کرتی ہے.اس کی ناپاک خطاؤں کو دنیا پر ظاہر ہونے
نہیں دیتی.کیونکہ عقلمند وحی کی روشنی کو پا کر اندر ہی اندر اپنی غلطیوں کی اصلاح کر لیتے ہیں اور
خدا کے پاک الہام کی برکت سے اپنے تئیں پردہ دری سے بچا لیتے ہیں.یہی وجہ ہے کہ
افلاطون کی طرح اسلام کے کسی فلاسفر نے کسی بت پر مرغ کی قربانی نہ چڑھائی.چونکہ
افلاطون الہام کی روشنی سے بے نصیب تھا.اس لئے دھوکا کھا گیا اور ایسا فلاسفر کہلا کر یہ مکروہ
اور احمقانہ حرکت اس سے صادر ہوئی.مگر اسلام کے حکماء کو ایسی ناپاک اور احمقانہ حرکتوں سے
ہمارے سید و مولیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نے بچالیا.اب دیکھو کیسا ثابت ہوا کہ
الہام عقلمندوں کا رات کی طرح پردہ پوش ہے.یہ بھی آپ لوگ جانتے ہیں کہ خدا کے کامل بندے آسمان کی طرح ہر ایک درماندہ کو اپنے
سایہ میں لے لیتے ہیں.خاص کر اس ذات پاک کے انبیاء اور الہام پانے والے عام طور پر
آسمان کی طرح فیض کی بارشیں برساتے ہیں.ایسا ہی زمین کی خاصیت بھی اپنے اندر رکھتے ہیں.ان کے نفس نفیس سے طرح طرح کے علوم عالیہ کے درخت نکلتے ہیں جن کے سایہ اور پھل اور
پھول سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں.سو یہ کھلا کھلا قانون قدرت جو ہماری نظر کے سامنے ہے اسی
چھپے ہوئے قانون کا ایک گواہ ہے جس کی گواہی کو قسموں کے پیرا یہ میں خدا تعالیٰ نے ان آیات
میں پیش کیا ہے.سو دیکھو کہ یہ کس قدر پر حکمت کلام ہے جو قرآن شریف میں پایا جاتا ہے.( اسلامی اصول کی فلاسفی، روحانی خزائن جلد 10 صفحہ 428424)
آیت وَ نَفْسٍ وَمَا سَوهَا - صاف طور پر بتلا رہی ہے کہ انسانِ کامل اپنے معنے اور
کیفیت کے رُو سے ایک عالم ہے اور عالم کبیر کے تمام شیون وصفات وخواص اجمالی طور پر
اپنے اندر جمع رکھتا ہے جیسا کہ اللہ جل شانہ نے شمس کی صفات سے شروع کر کے زمین تک جو
ہماری سکونت کی جگہ ہے سب چیزوں کے خواص اشارہ کے طور پر بیان فرمائے یعنی بطور
748
Page 757
قسموں کے ان کا ذکر کیا.بعد اس کے انسان کامل کے نفس کا ذکر فرمایا تا معلوم ہو کہ
انسان کامل کا نفس ان تمام کمالات متفرقہ کا جامع ہے جو پہلی چیزوں میں جن کی قسمیں کھائی گئیں
الگ الگ طور پر پائی جاتی ہیں.اور اگر یہ کہا جائے کہ خدائے تعالیٰ نے ان اپنی مخلوق چیزوں کی جو اس کے وجود کے
مقابل پر بے بنیاد و بیچ میں کیوں قسمیں کھائیں؟
تو اس کا جواب یہ ہے کہ تمام قرآن شریف میں یہ ایک عام عادت وسنت الہی ہے کہ وہ
بعض نظری امور کے اثبات و احقاق کے لئے ایسے امور کا حوالہ دیتا ہے جو اپنے خواص کا عام
طور پر بین اور کھلا کھلا نظر اور بدیہی ثبوت رکھتے ہیں.جیسا کہ اس میں کسی کو بھی شک نہیں ہو
سکتا کہ سورج موجود ہے اور اس کی دھوپ بھی ہے اور چاند موجود ہے اور وہ نور آفتاب سے
حاصل کرتا ہے اور روزِ روشن بھی سب کو نظر آتا ہے اور رات بھی سب کو دکھائی دیتی ہے اور
آسمان کا پول بھی سب کی نظر کے سامنے ہے اور زمین تو خود انسانوں کی سکونت کی جگہ ہے.اب
چونکہ یہ تمام چیزیں اپنا اپنا کھلا کھلا وجود اور کھلے کھلے خواص رکھتی ہیں جن میں کسی کو کلام نہیں ہو
سکتا اور نفس انسان
کا ایسی چھپی ہوئی اور نظری چیز ہے کہ خود اس کے وجود میں ہی صد با جھگڑے
برپا ہو رہے ہیں.بہت سے فرقے ایسے ہیں کہ وہ اس بات کو مانتے ہی نہیں کہ نفس یعنی روح
انسان بھی کوئی مستقل اور قائم بالذات چیز ہے جو بدن کی مفارقت کے بعد ہمیشہ کے لئے قائم
رہ سکتی ہے.اور جو بعض لوگ نفس کے وجود اور اس کی بقا اور ثبات کے قائل ہیں وہ بھی اُس کی
باطنی استعدادات کا وہ قدر نہیں کرتے جو کرنا چاہئے تھا.بلکہ بعض تو اتنا ہی سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم
صرف اسی غرض کے لئے دنیا میں آتے ہیں کہ حیوانات کی طرح کھانے پینے اور حظوظ نفسانی
میں عمر بسر کریں.وہ اس بات کو جانتے بھی نہیں کہ نفس انسانی کس قدر اعلیٰ درجہ کی طاقتیں اور
قوتیں اپنے اندر رکھتا ہے اور اگر وہ کسب کمالات کی طرف متوجہ ہو تو کیسے تھوڑے ہی عرصہ میں
تمام عالم کے متفرق کمالات و فضائل و انواع پر ایک دائرہ کی طرح محیط ہو سکتا ہے.749
Page 758
سو اللہ جل شانہ نے اس سورہ مبارکہ میں نفس انسان اور پھر اس کے بے نہایت خواص
فاضلہ کا ثبوت دینا چاہا ہے.پس اول اس نے خیالات کو رجوع دلانے کے لئے شمس اور قمر
وغیرہ چیزوں کے متفرق خواص بیان کر کے پھر نفس انسان کی طرف اشارہ فرمایا کہ وہ جامع ان
تمام کمالات متفرقہ کا ہے.اور جس حالت میں نفس میں ایسے اعلیٰ درجہ کے کمالات و خاصیات بہ
تمامہا موجود ہیں جو اجرام سماویہ اور ارضیہ میں متفرق طور پر پائے جاتے ہیں تو کمال درجہ کی
نادانی ہوگی کہ ایسے عظیم الشان اور مستجمع کمالات متفرقہ کی نسبت یہ وہم کیا جائے کہ وہ کچھ بھی
چیز نہیں جو موت کے بعد باقی رہ سکے.یعنی جب کہ یہ تمام خواص جو ان مشہود ومحسوس چیزوں
میں ہیں جن کا مستقل وجود ماننے میں تمہیں کچھ کلام نہیں یہاں تک کہ ایک اندھا بھی دھوپ کا
احساس کر کے آفتاب کے وجود کا یقین رکھتا ہے.نفس انسان میں سب کے سب یکجائی طور پر
موجود ہیں تو نفس کے مستقل اور قائم بالذات وجود میں تمہیں کیا کلام باقی ہے.کیا ممکن ہے کہ
جو چیز اپنی ذات میں کچھ بھی نہیں وہ تمام موجود بالذات چیزوں کے خواص جمع رکھتی ہو؟
اور اس جگہ قسم کھانے کی طرز کو اس وجہ سے اللہ جل شانہ نے پسند کیا ہے کہ قسم قائم مقام
شہادت کے ہوتی ہے.اسی وجہ سے حکام مجازی بھی جب دوسرے گواہ موجود نہ ہوں تو قسم پر
انحصار کر دیتے ہیں اور ایک مرتبہ کی قسم سے وہ فائدہ اٹھا لیتے ہیں جو کم سے کم دو گواہوں سے
اٹھا سکتے ہیں.سوچونکہ عقلاً وعرفا وقانوناً وشرعا قسم شاہد کے قائم مقام سمجھی جاتی ہے لہذا اسی بنا پر
خدائے تعالیٰ نے اس جگہ شاہد کے طور پر اس کو قرار دے دیا ہے.پس خدائے تعالیٰ کا یہ کہنا ہے کہ قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی درحقیقت اپنے
مرادی معنے یہ رکھتا ہے کہ سورج اور اس کی دھوپ یہ دونوں نفس انسان کے موجود بالذات اور
قائم بالذات ہونے کے شاہد حال ہیں.کیونکہ سورج میں جو جو خواص گرمی اور روشنی وغیرہ پائے
جاتے ہیں یہی خواص مع سے زائد انسان کے نفس میں بھی موجود ہیں.مکاشفات کی روشنی اور
توجہ کی گرمی جو نفوس کاملہ میں پائی جاتی ہے اس کے عجائبات سورج کی گرمی اور روشنی سے کہیں
750
Page 759
بڑھ کر ہیں.سو جب کہ سورج موجود بالذات ہے تو جو خواص میں اس کا ہم مثل اور ہم پلہ ہے
بلکہ اس سے بڑھ کر یعنی نفس انسان وہ کیوں کر موجود بالذات نہ ہوگا.اسی طرح خدائے تعالیٰ کا یہ کہنا کہ قسم ہے چاند کی جب وہ سورج کی پیروی کرے.اس
کے مرادی معنے یہ ہیں کہ چاند اپنی اس خاصیت کے ساتھ کہ وہ سورج سے بطور استفادہ نور
حاصل کرتا ہے نفس انسان کے موجود بالذات اور قائم بالذات ہونے پر شاہدِ حال ہے کیونکہ
جس طرح چاند سورج سے اکتساب نور کرتا ہے اسی طرح نفس انسان کا جو مستعد اور طالب حق
ہے ایک دوسرے انسان کامل کی پیروی کر کے اس کے نور میں سے لے لیتا ہے اور اس کے
باطنی فیض سے فیضیاب ہو جاتا ہے بلکہ چاند سے بڑھ کر استفادہ نور کرتا ہے کیونکہ چاند تو نور کو
حاصل کر کے پھر چھوڑ بھی دیتا ہے مگر یہ
کبھی نہیں چھوڑتا.پس جبکہ استفادہ نور میں یہ چاند کا
شریک غالب ہے اور دوسری تمام صفات اور خواص چاند کے اپنے اندر رکھتا ہے تو پھر کیا وجہ
کہ چاند کو تو موجود بالذات اور قائم بالذات مانا جائے مگر نفس انسان کے مستقل طور پر موجود
ہونے سے بکنی انکار کر دیا جائے.غرض اسی طرح خدائے تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو جن کا ذکر نفس انسان کی پہلے قسم کھا کر
کیا گیا ہے اپنے خواص کے رو سے شواہد اور ناطق گواہ قرار دے کر اس بات کی طرف توجہ دلائی
ہے کہ نفس انسان واقعی طور پر موجود ہے.اور اسی طرح ہر یک جگہ جو قرآن شریف میں بعض
بعض چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں ان قسموں سے ہر جگہ یہی مدعا اور مقصد ہے کہ تا امر بدیہہ کو
اسرار مخفیہ کے لئے جو اُن کے ہم رنگ ہیں بطور شواہد کے پیش کیا جائے.لیکن اس جگہ یہ سوال ہوگا کہ جو نفس انسان کے موجود بالذات ہونے کے لئے قسموں کے
پیرا یہ میں شواہد پیش کئے گئے ہیں ان شواہد کے خواص بدیہی طور پر نفس انسان میں کہاں پائے
جاتے ہیں اور اس کا ثبوت کیا ہے کہ پائے جاتے ہیں.اس وہم کے رفع کرنے کے لئے
اللہ جل شانہ اس کے بعد فرماتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقُوهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّهَا وَقَدْ خَابَ
751
Page 760
مَنْ دَشَهَا.یعنی خدائے تعالیٰ نے نفس انسان کو پیدا کر کے ظلمت اور نورانیت اور ویرانی اور
سرسبزی کی دونوں راہیں اس کے لئے کھول دی ہیں.جو شخص ظلمت اور فجور یعنی بدکاری کی
را ہیں اختیار کرے تو اس کو ان راہوں میں ترقی کے کمال درجہ تک پہنچایا جاتا ہے یہاں تک
کہ اندھیری رات سے اس کی سخت مشابہت ہو جاتی ہے اور بجز معصیت اور بدکاری اور
پر ظلمت خیالات کے اور کسی چیز میں اس کو مزہ نہیں آتا.ایسے ہی ہم صحبت اس کو اچھے معلوم
ہوتے ہیں اور ایسے ہی شغل اس کے جی کو خوش کرتے ہیں اور اس کی بدطبیعت کے
مناسب حال بدکاری کے الہامات اس کو ہوتے رہتے ہیں.یعنی ہر وقت بدچلنی اور بدمعاشی
کے ہی خیالات اس کو سو جھتے ہیں.کبھی اچھے خیالات اس کے دل میں پیدا ہی نہیں ہوتے اور
اگر پرہیز گاری کا نورانی راستہ اختیار کرتا ہے تو اس نور کو مدد دینے والے الہام اس کو ہوتے
رہتے ہیں.یعنی خدائے تعالیٰ اس کے دلی نور کو جو تخم کی طرح اس کے دل میں موجود ہے اپنے
الہامات خاصہ سے کمال تک پہنچا دیتا ہے اور اس کے روشن مکاشفات کی آگ کو افروختہ کر
دیتا ہے.تب وہ اپنے چمکتے ہوئے نور کو دیکھ کر اور اس کے افاضہ اور استفاضہ کی خاصیت کو
آزما کر پورے یقین سے سمجھ لیتا ہے کہ آفتاب اور ماہتاب کی نورانیت مجھ میں بھی موجود ہے.اور آسمان کے وسیع اور بلند اور پر کواکب ہونے کے موافق میرے سینہ میں بھی انشراح صدر اور
عالی ہمتی اور دل اور دماغ میں ذخیرہ روشن قویٰ کا موجود ہے جو ستاروں کی طرح چمک رہے
ہیں.تب اسے اس بات کے سمجھنے کے لئے اور کسی خارجی ثبوت کی کچھ بھی ضرورت نہیں ہوتی
بلکہ اس کے اندر سے ہی ایک کامل ثبوت کا چشمہ ہر وقت جوش مارتا ہے اور اس کے پیاسے
دل کو سیراب کرتا رہتا ہے.اور اگر یہ سوال پیش ہو کہ سلوک کے طور پر کیوں کر ان نفسانی خواص کا مشاہدہ ہو سکے تو اس
کے جواب میں اللہ جل شانہ فرماتا ہے.قَد أَفْلَحَ مَنْ زَكَّهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَشْهَا یعنی جس
شخص نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا اور بکنی رذائل اور اخلاق ذمیمہ سے دست بردار ہو کر
752
Page 761
خدائے تعالیٰ کے حکموں کے نیچے اپنے تئیں ڈال دیا وہ اس مراد کو پہنچے گا اور اپنا نفس اس کو
عالم صغیر کی طرح کمالات متفرقہ کا مجمع نظر آئے گا.لیکن جس شخص نے اپنے نفس کو پاک نہیں
کیا بلکہ بیجا خواہشوں کے اندر گاڑ دیا وہ اس مطلب کے پانے سے نامرادر ہے گا.ما حصل اس تقریر کا یہ ہے کہ بلا شبہ نفس انسان میں وہ متفرق کمالات موجود ہیں جو تمام عالم
میں پائے جاتے ہیں اور ان پر یقین لانے کے لئے یہ ایک سیدھی راہ ہے کہ انسان
حسب منشائے قانون الہی تزکیہ نفس کی طرف متوجہ ہو.کیوں کہ تزکیہ نفس کی حالت میں نہ
صرف علم الیقین بلکہ حق الیقین کے طور پر ان کمالات مخفیہ کی سچائی کھل جائے گی.پھر بعد اس کے اللہ جل شانہ ایک مثال کے طور پر ثمود کی قوم کا ذکر کر کے فرماتا ہے کہ
انہوں نے بباعث اپنی جبلی سرکشی کے اپنے وقت کے نبی کو جھٹلایا اور اس کی تکذیب کے لئے
ایک بڑا بد بخت ان میں سے پیش قدم ہوا.اس وقت کے رسول نے انہیں نصیحت کے طور پر کہا
کہ ناقتہ اللہ یعنی خدائے تعالیٰ کی اونٹنی اور اس کے پانی پینے کی جگہ کا تعرض مت کرو مگر انہوں نے
نہ مانا اور اونٹنی کے پاؤں کاٹے.سو اس جرم کی شامت سے اللہ تعالیٰ نے ان پر موت کی مارڈالی
اور انہیں خاک سے ملا دیا اور خدائے تعالیٰ نے اس بات کی کچھ بھی پرواہ نہ کی کہ ان کے مرنے
کے بعد ان کی بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں اور بے کس عیال کا کیا حال ہوگا.یہ ایک نہایت لطیف مثال ہے جو خدائے تعالیٰ نے انسان کے نفس کو ناقۃ اللہ سے
مشابہت دینے کے لئے اس جگہ لکھی ہے.مطلب یہ ہے کہ انسان کا نفس بھی درحقیقت اسی
غرض کے لئے پیدا کیا گیا ہے کہ تاوہ ناقتہ اللہ کا کام دیوے.اس کے فنا فی اللہ ہونے کی
حالت میں خدائے تعالیٰ اپنی پاک محلی کے ساتھ اس پر سوار ہو جیسے کوئی اونٹنی پر سوار
ہوتا ہے.سونفس پرست لوگوں کو جو حق سے منہ پھیر رہے ہیں تہدید اور انذار کے طور پر فرمایا
کہ تم لوگ بھی قوم ثمود کی طرح ناقتہ اللہ کا سفیا یعنی اس کے پانی پینے کی جگہ جو یاد الہی اور
معارف الہی کا چشمہ ہے جس پر اس ناقہ کی زندگی موقوف ہے اس پر بند کر رہے ہو اور نہ صرف
753
Page 762
بند بلکہ اس کے پیر کاٹنے کی فکر میں ہوتا وہ خدائے تعالیٰ کی راہوں پر چلنے سے بالکل رہ جائے.سوا اگر تم اپنی خیر مانگتے ہو تو وہ زندگی کا پانی اس پر بندمت کر دو اور اپنی بے جا خواہشوں کے
تیر و تبر سے اس کے پیر مت کاٹو.اگر تم ایسا کرو گے اور وہ ناقہ جو خدائے تعالیٰ کی سواری کے
لئے تم کو دی گئی ہے مجروح ہو کر مر جائے گی تو تم بالکل سکتے اور خشک لکڑی کی طرح متصور ہو کر
کاٹ دیے جاؤ گے اور پھر آگ میں ڈالے جاؤ گے اور تمہارے مرنے کے بعد خدائے تعالیٰ
تمہارے پس ماندوں پر ہر گز رحم نہیں کرے گا بلکہ تمہاری معصیت اور بدکاری کا وبال ان کے
بھی آگے آئے گا اور نہ صرف تم اپنی شامت اعمال سے مرو گے بلکہ اپنے عیال واطفال کو بھی اسی
تباہی میں ڈالو گے.ان آیات بینات سے صاف صاف ثابت ہو گیا کہ خداوند کریم نے انسان کو سب مخلوقات
سے بہتر اور افضل بنایا ہے اور ملائک اور کواکب اور عناصر وغیرہ جو کچھ انسان میں اور
خدائے تعالیٰ میں بطور وسائط کے دخیل ہو کر کام کر رہے ہیں وہ اُن کا درمیانی واسطہ ہونا ان کی
افضلیت پر دلالت نہیں کرتا.اور وہ اپنے درمیانی ہونے کی وجہ سے انسان کو کوئی عزت نہیں
بخشتے بلکہ خود اُن کو عزت حاصل ہوتی ہے کہ وہ ایسی شریف مخلوق کی خدمت میں لگائے گئے
ہیں سو در حقیقت وہ تمام خادم ہیں، نہ مخدوم.توضیح مرام، روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 79 تا 85)
فَالْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقُوهَا
حمد اس کے تو صرف اسی قدر معنی ہیں کہ خدائے تعالی بوجہ علت العلل ہونے کے بدوں
کو اُن کے مناسب حال اور نیکوں کو اُن کے مناسب حال اُن کے جذبات نفسانی یا متقیانہ
جوشوں کے موافق اپنے قانون قدرت کے حکم سے خیالات و تدابیر ویل مطلوبہ کے ساتھ تائید
دیتا ہے یعنی نئے نئے خیالات وحیل مطلوبہ اُن کو سوجھا دیتا ہے یا یہ کہ اُن کے ان جوشوں اور
جذبوں کو بڑھاتا ہے اور یا یہ کہ اُن کے تخم مخفی کو ظہور میں لاتا ہے.مثلا ایک چور اس خیال میں
لگا رہتا ہے کہ کوئی عمدہ طریقہ نقب زنی کا اس کو معلوم ہو جائے تو اس کو سوجھایا جاتا ہے.یا
754
Page 763
ایک متقی چاہتا ہے کہ وجہ حلال کی قوت کے لئے کوئی سبیل مجھے حاصل ہو تو اس بارہ میں اس کو
بھی کوئی طریق بتلایا جاتا ہے.سو عام طور پر اس کا نام الہام ہے جو کسی نیک بخت یا بد بخت
سے خاص نہیں بلکہ تمام نوع انسان اور جمیع افراد بشر اس علۃ العلل سے مناسب حال اپنے اس
الہام سے مستفیض ہورہے ہیں.(ازالہ اوہام ، روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 597، 598)
خدا تعالیٰ نے انسان کے لئے ابتلا کے طور پر دو روحانی داعی مقرر کر رکھے ہیں.ایک
داعی خیر جس کا نام روح القدس ہے اور ایک دائی شر جس کا نام ابلیس اور شیطان ہے.یہ دونوں
دائی صرف خیر یا شر کی طرف بلاتے رہتے ہیں مگر کسی بات پر جبر نہیں کرتے جیسا کہ اس
آیت کریمہ میں اسی امر کی طرف اشارہ ہے فَالْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقُوهَا.یعنی خدا بدی کا بھی
الہام کرتا ہے اور نیکی کا بھی.بدی کے الہام کا ذریعہ شیطان ہے جو شرارتوں کے خیالات دلوں
میں ڈالتا ہے اور نیکی کے الہام کا ذریعہ روح القدس ہے جو پاک خیالات دل میں ڈالتا ہے اور
چونکہ خدا تعالیٰ علت العلل ہے اس لئے یہ دونوں الہام خدا تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کر
لئے کیونکہ اسی کی طرف سے یہ سارا انتظام ہے ورنہ شیطان کیا حقیقت رکھتا ہے جو کسی کے دل
میں وسوسہ ڈالے اور روح القدس کیا چیز جو کسی کو تقویٰ کی راہوں کی ہدایت کرے.) آئینہ کمالات اسلام، روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 80، 81 حاشیہ)
بلا شبہ وہ تمام عمدہ باتیں جن سے انسانوں کو نفع پہنچتا ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے دل
میں ڈالی جاتی ہیں جیسا کہ اللہ جل شانہ بھی در حقیقت اسی کی طرف اشارہ فرما کر کہتا ہے
فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَ تَقُوهَا یعنی بُری باتیں اور نیک باتیں جو انسانوں کے دلوں میں پڑتی ہیں وہ
خدا تعالیٰ کی طرف سے ہی الہام ہوتی ہیں اچھا آدمی اپنی اچھی طبیعت کی وجہ سے اس لائق ہوتا
ہے کہ اچھی باتیں اس کے دل میں پڑیں اور بُرا آدمی اپنی بُری طبیعت کی وجہ سے اس لائق
ٹھہرتا ہے کہ بُرے خیالات اور بد اندیشی کی تجویزیں اُس کے دل میں پیدا ہوتی رہیں اور
در حقیقت نیک انسان اس قسم کے الہامات کے حاصل کرنے کے لئے فطرتاً ایک نیک ملکہ
755
Page 764
اپنے اندر رکھتا ہے اور بُرا انسان فطرتاً ایک بُرا ملکہ رکھتا ہے چنانچہ اسی ملکہ فطرتی کی وجہ سے
بہت سے لوگ اچھی اور بری تالیفیں اور پاک اور ناپاک ملفوظات اپنی یادگار چھوڑ گئے ہیں.بركات الدعا، روحانی خزائن جلد 6 صفحہ 20 حاشیہ )
وہ شخص نجات پا گیا جس نے اپنی جان کو غیر کے خیال سے پاک کیا.اس آیت میں یہ
نہیں کہا کہ جس نے اس محبوب کو اپنے اندر آباد کیا....حقیقت یہ ہے کہ خدا تعالیٰ تو اندر میں خود
آباد ہے صرف انسان کی طرف سے بوجہ التفات إلى الغير دُوری ہے.پس جس وقت غیر کی
طرف سے التفات کو ہٹالیا تو خود اپنے اندر نور الہی کو مشاہدہ کرلے گا.خدا د ور نہیں ہے کہ کوئی اس
طرف جاوے یا وہ اس طرف آوے بلکہ انسان اپنے حجاب سے آپ ہی اس سے دُور ہے.پس خدا
فرماتا ہے کہ جس نے آئینہ دل کو صاف کر لیا وہ دیکھ لے گا کہ خدا اس کے پاس ہی ہے.ست بچن، روحانی خزائن جلد 10 صفحه 223)
مذہب اُس زندگی کے حاصل کرنے کے لئے ہے جو خدا میں ہے اور وہ زندگی نہ کسی
کو حاصل ہوئی اور نہ آئندہ ہوگی بجز اس کے کہ خدائی صفات انسان کے اندر داخل ہو جائیں.خدا کے لئے سب پر رحم کرو تا آسمان سے تم پر رحم ہو.آؤ میں تمہیں ایک ایسی راہ سکھاتا ہوں جس
سے تمہارا نور تمام نوروں پر غالب رہے اور وہ یہ ہے کہ تم تمام سفلی کینوں اور حسدوں کو چھوڑ دو
اور ہمدر دنوع انسان ہو جاؤ اور خدا میں کھوئے جاؤ اور اس کے ساتھ اعلیٰ درجہ کی صفائی حاصل کرو
کہ یہی وہ طریق ہے جس سے کرامتیں صادر ہوتی ہیں اور دعائیں قبول ہوتی ہیں اور فرشتے مدد
کے لئے اترتے ہیں.مگر یہ ایک دن کا کام نہیں ترقی کر و تر قی کرو.اس دھوبی سے سبق سیکھو جو
کپڑوں کو اؤل بھٹی میں جوش دیتا ہے اور دئیے جاتا ہے یہاں تک کہ آخر آگ کی تاثیریں
تمام میل اور چرک کو کپڑوں سے علیحدہ کر دیتی ہیں.تب صبح اٹھتا ہے اور پانی پر پہنچتا ہے اور
پانی میں کپڑوں کو تر کرتا ہے.اور بار بار پتھروں پر مارتا ہے تب وہ میل جو کپڑوں کے اندر تھی
اور اُن کا جز بن گئی تھی کچھ آگ سے صدمات اٹھا کر اور کچھ پانی میں دھوبی کے بازو سے مارکھا
کر یکدفعہ جدا ہونی شروع ہو جاتی ہے یہاں تک کہ کپڑے ایسے سفید ہو جاتے ہیں جیسے ابتدا
756
Page 765
میں تھے.یہی انسانی نفس کے سفید ہونے کی تدبیر ہے اور تمہاری ساری نجات اس سفیدی پر
موقوف ہے.یہی وہ بات ہے جو قرآن شریف میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَعَهَا
یعنی وہ نفس نجات پا گیا جو طرح طرح کے میلوں اور چرکوں سے پاک کیا گیا.( گورنمنٹ انگریزی اور جہاد، روحانی خزائن جلد 17 صفحه 15-14)
قرآن شریف میں آیا ہے قد أَفْلَحَ مَن زَکھا اس نے نجات پائی جس نے اپنے نفس کا
تزکیہ کیا.تزکیہ نفس کے واسطے صحبت صالحین اور نیکوں کے ساتھ تعلق پیدا کرنا بہت مفید
ہے.جھوٹ وغیرہ اخلاق رذیلہ دور کرنے چاہئیں اور جو راہ پر چل رہا ہے اس سے راستہ پوچھنا
چاہئے.اپنی غلطیوں کو ساتھ ساتھ درست کرنا چاہئے جیسا کہ غلطیاں نکالنے کے بغیر املا درست
نہیں ہوتا ویسا ہی غلطیاں نکالنے کے بغیر اخلاق بھی درست نہیں ہوتے آدمی ایسا جانور ہے کہ
اس کا تزکیہ ساتھ ساتھ ہوتا رہے تو سیدھی راہ پر چلتا ہے ورنہ بہک جاتا ہے.ملتا
( بدر جلد 10 نمبر 44، 45 مورخہ 5اکتوبر 1911 صفحہ 9)
دنیا میں انسان کو جو بہشت حاصل ہوتا ہے وہ قَد أَفْلَحَ مَنْ زَلهَا پر عمل کرنے سے
ہے.جب انسان عبادت کا اصل مفہوم اور مغز حاصل کر لیتا ہے تو خدا تعالیٰ کے
انعام واکرام کا پاک سلسلہ جاری ہو جاتا ہے اور جو نعمتیں آئندہ بعد مردن ظاہری، مرتی اور محسوس
طور پر ملیں گی وہ اب روحانی طور پر پاتا ہے.الحکم جلد 6 نمبر 26 مورخہ 24 جولائی 1902، صفحہ 9)
کپڑا جب تک سارا نہ دھویا جاوے وہ پاک نہیں ہوسکتا.اسی طرح پر انسان کے
سارے جوارح اس قابل ہیں کہ وہ دھوئے جاویں کسی ایک کے دھونے سے کچھ نہیں ہوتا.الحکم جلد 5 نمبر 40 مورخہ 31 اکتوبر 1901 ، صفحہ 1)
یا درکھو کہ اصل صفائی وہی ہے جو فرمایا
ہے قد افلح من رکھا.ہر
شخص اپنا فرض سمجھ
لے کہ وہ اپنی حالت میں تبدیلی کرے.الحکم جلد 6 نمبر 12 مورخہ 31 مارچ 1902ء صفحہ 6)
757
Page 766
پاکیزگی اور طہارت عمدہ شے ہے.انسان پاک اور مطہر ہو تو فرشتے اس سے مصافحہ
کرتے ہیں.لوگوں میں اس کی قدر نہیں ہے ورنہ ان کی لذات کی ہر ایک شے حلال ذرائع
سے ان کو ملے.چور چوری کرتا ہے کہ مال ملے لیکن اگر صبر کرے تو خدا تعالیٰ اسے اور راہ سے
مالدار کر دے.اسی طرح زانی زنا کرتا ہے اگر صبر کرے تو خدا اس کی خواہش کو اور راہ سے
پوری کر دے.جس میں اس کی رضا حاصل ہو.حدیث میں ہے کہ کوئی چور چوری نہیں کرتا مگر
اس حالت میں کہ وہ مومن نہیں ہوتا اور کوئی زانی زنا نہیں کرتا مگر اس حالت میں کہ وہ مومن
نہیں ہوتا.جیسے بکری کے سر پر شیر کھڑا ہو تو وہ گھاس بھی نہیں کھا سکتی.تو بکری جتنا ایمان بھی
لوگوں کا نہیں ہے.اصل جڑا اور مقصود تقویٰ ہے جسے وہ عطا ہو تو سب کچھ پاسکتا ہے بغیر اس
کے ممکن نہیں ہے کہ انسان صفائز اور کبائر سے بچ سکے.( البدر جلد 1 نمبر 7 مورخہ 12 دسمبر 1902ء صفحہ 51)
ی فلاح نہیں ہوتی جب تک نفس کو پاک نہ کرے اور نفس تب ہی پاک ہوتا ہے جب
اللہ تعالیٰ کے احکام کی عزت اور ادب کرے اور ان راہوں سے بچے جو دوسرے کے آزار اور
دکھ کا موجب ہوتی ہیں.احکم جلد 9 نمبر 33 مورخہ 24 ستمبر 1905 ، صفحہ 9)
اسلام نے...تعليم دى قد أَفْلَحَ مَنْ زَهَا یعنی نجات پا گیا وہ شخص جس نے تزکیہ
نفس کیا.یعنی جس نے ہر قسم کی بدعت، فسق و فجور، نفسانی جذبات سے خدا تعالیٰ کے لئے الگ
کر لیا اور ہر قسم کی نفسانی لذات کو چھوڑ کر خدا کی راہ میں تکالیف کو مقدم کر لیا.ایسا شخص
فی الحقیقت نجات یافتہ ہے جو خدا تعالیٰ کو مقدم کرتا ہے اور دنیا اور اس کے تکلفات کو چھوڑتا
ہے.اور پھر فرمایا قَد خَابَ مَنْ دَشها مٹی کے برابر ہو گیا وہ شخص جس نے نفس کو آلودہ کر لیا
یعنی جو زمین کی طرف جھک گیا.گویا یہ ایک ہی فقرہ قرآن کریم کی ساری تعلیمات کا خلاصہ
ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کس طرح خدا تعالیٰ تک پہنچتا ہے.یہ بالکل سچی اور پکی
758
Page 767
بات ہے کہ جب تک انسان قوی بشریہ کے برے طریق کو نہیں چھوڑتا اس وقت تک خدا نہیں
ملتا.دنیا کی گندگیوں سے نکلنا چاہتے ہو اور خدا تعالیٰ کو ملنا چاہتے ہو تو ان لذات کو ترک کرو.الحکم جلد 10 نمبر 21 مورخہ 17 جون 1906 صفحہ 3)
قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّهَا
اس نے نجات پائی جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا.لیکن تزکیہ نفس بھی ایک موت
ہے.جب تک کہ گل اخلاق رذیلہ کو ترک نہ کیا جاوے تزکیہ نفس کہاں حاصل ہوسکتا ہے.ہر
ایک شخص میں کسی نہ کسی شر کا مادہ ہوتا ہے وہ اس کا شیطان ہوتا ہے جب تک کہ اس کو قتل نہ
کرے کام نہیں بن سکتا.( اخبار بدر جلد 6 نمبر 18 مورخہ 2 مئی 1907ء صفحہ 2)
آیت قرآنی قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّهَا وَقَدْ خَابَ مَن دَشها کا ترجمہ اردو میں ایک دفعہ
سوچتا تھا تو یہ شعر لکھا گیا..کوئی اس پاک سے جو دل لگاوے کرے پاک آپ کو تب اس کو پاوے
( بدر جلد 6 نمبر 47 مورخہ 21 نومبر 1907 صفحه 10)
یا درکھو کہ خدا کا یہ ہرگز منشاء نہیں کہ تم دنیا کو بالکل ترک کرد و بلکہ اس کا جو منشاء ہے وہ یہ
ہے کہ قد أفلح من زكها - تجارت کرو، زراعت کرو، ملازمت کرو اور حرفت کرو، جو چاہو کرو
مگر نفس کو خدائی نافرمانی سے روکتے رہو اور ایسا تزکیہ کرو کہ یہ امور تمہیں خدا سے غافل نہ کر
دیں.پھر جو تمہاری دنیا ہے وہ بھی دین کے حکم میں آجاوے گی.الحکم جلد 12 نمبر 49، 50 مورخہ 26، 30 اگست 1908 صفحہ 4)
تزکیۂ نفس بڑا مشکل مرحلہ ہے اور مدار نجات تزکیہ نفس پر موقوف ہے.اللہ تعالیٰ
فرماتا ہے قد أَفْلَحَ مَنْ زَكها اور تزکیہ نفس بجر فضل خدا میسر نہیں آسکتا.( الحکم جلد 12 نمبر 33 مورخہ 14 مئی 1908 ، صفحہ 4)
تزکیہ نفس میں ہی تمام برکات اور فیوض اور کامیابیوں کا راز پنہاں ہے.فلاح صرف
امور دینی ہی میں نہیں بلکہ دنیا و دین میں کامیابی ہوگی.نفس کی ناپاکی سے بچنے والا انسان کبھی
759
Page 768
نہیں ہوسکتا کہ وہ دنیا میں ذلیل ہو.الحکم جلد 12 نمبر 41 مورخہ 14 جولائی 1908 ، صفحہ 4)
تم لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ تزکیۂ نفس کس کو کہا جاتا ہے.سو یا درکھو کہ ایک مسلمان کو
حقوق اللہ اور حقوق العباد کو پورا کرنے کے واسطے ہمہ تن تیار رہنا چاہئے اور جیسے زبان سے
خدا تعالیٰ کو اس کی ذات اور صفات میں وحدہ لاشریک سمجھتا ہے ویسے ہی عملی طور پر اس کو
دکھانا چاہئے اور اس کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی اور ملائمت سے پیش آنا چاہئے اور اپنے بھائیوں
سے کسی قسم کا بھی بغض، حسد اور کینہ نہیں رکھنا چاہئے اور دوسروں کی غیبت کرنے سے بالکل
الگ ہوجانا چاہئے.لیکن میں دیکھتا ہوں کہ یہ معاملہ تو ابھی ڈور ہے کہ تم لوگ خدا کے ساتھ ایسے
از خود رفتہ اور محو ہو جاو کہ بس اسی کے ہو جاو اور جیسے زبان سے اس کا اقرار کرتے ہو عمل سے بھی
کر کے دکھاؤ.ابھی تو تم لوگ مخلوق کے حقوق کو بھی کما حقہ ادا نہیں کرتے.بہت سے ایسے
ہیں جو آپس میں فساد اور دشمنی رکھتے ہیں اور اپنے سے کمزور اور غریب شخصوں کو نظر حقارت سے
دیکھتے ہیں اور بدسلوکی سے پیش آتے ہیں اور ایک دوسرے کی غیبتیں کرتے اور اپنے دلوں میں
بغض اور کینہ رکھتے ہیں لیکن خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم آپس میں ایک وجود کی طرح بن جاؤ اور
جب تم ایک وجود کی طرح ہو جاؤ گے اس وقت کہہ سکیں گے کہ اب تم نے اپنے نفسوں
کا تزکیہ کر
لیا.کیونکہ جب تک تمہارا آپس میں معاملہ صاف نہیں ہوگا اس وقت تک خدا تعالیٰ سے بھی
معاملہ صاف نہیں ہو سکتا گوان دونوں قسم کے حقوقوں میں بڑا حق خدا تعالیٰ کا ہے مگر اس کی مخلوق
کے ساتھ معاملہ کرنا یہ بطور آئینہ کے ہے.جو شخص اپنے بھائیوں سے صاف صاف معاملہ
نہیں کرتا وہ خدا کے حقوق بھی ادا نہیں کرسکتا.حکم جلد 12 نمبر 2 مورخہ 3 جنوری 1908ء)
ہدایتِ الہی تو یہ ہے کہ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَشْهَا.نجات پائے گا
و شخص جس نے تزکیہ نفس کیا اور بلاک ہو گیا وہ آدمی جس نے نفس کو بگاڑا.طلح چیرنے کو
کہتے ہیں.فلاحت زراعت کو جانتے ہو.تزکیہ نفس میں بھی فلاحت ہے.مجاہدہ انسانی نفس کو
760
Page 769
اس کی خرابیوں اور سختیوں سے صاف کر کے اس قابل بنا دیتا ہے کہ اس میں ایمان صحیحہ کی
تخم ریزی کی جاوے.پھر وہ شجر ایمان بارور ہونے کے لائق بن جاتا ہے.چونکہ ابتدائی
مراحل اور منازل میں منتقی کو بڑی بڑی مصائب اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس لئے
فلاح سے تعبیر کیا ہے.رپورٹ جلسہ سالانہ 1897 صفحہ (154)
بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی بدکاریاں اور شوخیاں اس حد تک پہنچی ہوئی ہوتی
ہیں کہ جب وہ خدا کے غضب سے ہلاک ہوتا ہے تو اس لعنت اور غضب کا اثر اس کی اولاد تک
بھی پہنچتا ہے.اسی لئے قرآن شریف میں فرمایا گیا ہے وَلَا يَخَافُ عُقْبَهَا عُقْبَهَا
اولاد اور پسماندگان مراد ہیں.الحکم جلد 6 نمبر 21 مورخہ 10 جون 1902 ، صفحہ 8
حدیث شریف اور قرآن مجید سے ثابت ہے اور ایسا ہی پہلی کتابوں سے بھی پایا جاتا ہے
کہ والدین کی بدکاریاں بچوں پر بھی بعض وقت آفت لاتی ہیں.اسی کی طرف اشارہ ہے ولا تخافی
عقبها - جولوگ لااُبالی زندگی بسر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے بے پرواہ ہو جاتا ہے.دیکھو دنیا میں جو اپنے آقا کو چند روز سلام نہ کرے تو اس کی نظر بگڑ جاتی ہے تو جو خدا سے قطع کرے
پھر خدا اس کی پرواہ کیوں کرے گا اسی پر وہ فرماتا ہے کہ وہ ان کو بلاک کر کے ان کی اولاد کی بھی
پرواہ نہیں کرتا.اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو متقی صالح مرجاوے اس کی اولاد کی پرواہ کرتا ہے.الحکم جلد 7 نمبر 12 مورخہ 31 اگست 1903ء صفحه 10)
دیکھو جب کوئی بادشاہ کے کسی امر کے متعلق سمجھادے کہ تم اس سے رک جاؤ تمہارا
بھلا ہوگا تو اگر وہ شخص رک جاوے تو بہتر ورنہ پھر اس کا عذاب کیسا سخت ہوتا ہے.اسی طرح
پہلے چھوٹے چھوٹے عذابوں سے خدا تعالیٰ لوگوں کو سمجھوتیاں دیتا ہے کہ باز آجاؤ موقع ہے
ور نہ پچھتاؤ گے مگر جیسا وہ نہیں سمجھتے اور اس کی نافرمانی سے نہیں رکتے تو پھر اس کا عذاب ایسا
ہوتا ہے.لَا يَخَافُ عُقبها -
الحکم جلد 7 نمبر 12 مورخہ 31 مارچ 1903 ، صفحہ 10)
761
Page 770
وہ آدمی جو احکام الہی کی پرواہ نہیں کرتا خدا بھی اس کی پرواہ نہیں کرتا جیسا کہ
آیت کریمہ وَلا يَخافُ عُقبها سے ظاہر ہے.یعنی نافرمانوں پر جب وہ عذاب کرنے پر آتا
ہے تو ایسی لا ابالی سے عذاب کرتا ہے کہ عذاب کی ہلاکت سے ان کے بال بچوں کی بھی پرواہ
نہیں کرتا کہ ان کا حال ان کے نافرمان والدین کے بعد کیا ہوگا.الحکم جلد 9 نمبر 5 موخہ 10 فروری 1905، صفحہ 4
خدا تعالیٰ کی عظمت کو دل میں رکھنا چاہئے.اور اس سے ہمیشہ ڈرنا چاہئے اس کی گرفت
خطر ناک ہوتی ہے.وہ چشم پوشی کرتا ہے اور در گذر فرماتا ہے لیکن جب کسی کو پکڑتا ہے تو پھر
بہت سخت پکڑتا ہے یہاں تک کہ لا يَخافُ عُقبها.پھر وہ اس امر کی بھی پرواہ نہیں کرتا کہ اس
کے پچھلوں کا کیا حال ہو گا.برخلاف اس کے جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے اور اس کی عظمت کو دل
میں جگہ دیتے ہیں خدا تعالیٰ ان کو عزت دیتا اور خود ان کے لئے ایک سپر ہو جاتا ہے.الحکم جلد 10 نمبر 21 مورخہ 17 جون 1906، صفحہ 3)
جولوگ انبیاء کی زندگی میں فسق و فجور میں مبتلا رہتے ہیں اور عاقبت کی کچھ فکر نہیں کرتے
اور راستبازوں پر حملے کرتے ہیں ایسوں ہی کی نسبت خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَخَافُ عُقْبَهَا
اس سے مراد یہ ہے کہ جب ایک موذی بے ایمان کو اللہ کریم مارتا ہے تو پھر کچھ پرواہ نہیں رکھتا کہ اس
کے عیال اطفال کا گزارہ کس طرح ہوگا اور اس کے پسماندہ کیسی حالت میں بسر کریں گے.(احکم جلد 11 نمبر 34 مورخہ 24 ستمبر 1907، صفحہ 4)
حضرت خلیفہ المسیح الثانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:
وَالشَّمس ہم شہادت کے طور پر پیش کرتے ہیں سورج کو وضحها اور اس کی اس
روشنی کو جو اس کی ذاتی روشنی ہے.وَالْقَمَرِ إِذا تلها ہم چاند کو شہادت کے طور پر پیش کرتے ہیں مگر خالی چاند کو نہیں بلکہ
چاند کی اس حالت میں شہادت کے طور پر پیش کرتے ہیں جب وہ کامل طور پر سورج کے سامنے
آجاتا ہے اور اس کی روشنی کو جذب کر کے دوسری دنیا کو منور کر دیتا ہے.762
Page 771
وَالنَّهَارِ إِذَا جَلُّهَا
جب ہم دن کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کے یہ معنے نہیں ہوتے کہ سورج چمکنے لگ گیا
ہے کیونکہ سورج تو ہر وقت چمکتا رہتا ہے.دن سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ہماری زمین سورج کے
سامنے آگئی ہے پس وَالنَّهَارِ إِذَا جَلْهَا کے یہ معنے ہوئے کہ جب زمین نے سورج کے سامنے
آکر سورج کو دکھا دیا.صحھا کا مطلب اور تھا.ضُحھا سے سورج کی ذاتی روشنی کی طرف اشارہ
تھا خواہ وہ دنیا کے سامنے ہو یا نہ ہو سورج بہر حال چمک رہا ہوتا ہے اس کے سامنے بادل آجائیں
یا زمین اس کی طرف سے رخ بدل لے اس کی ذاتی روشنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا.لیکن باوجود
سورج کے ہر وقت چمکتے رہنے کے رات کے وقت کو نہار نہیں کہیں گے کیونکہ نہار یا دن اس
وقت کو کہتے ہیں جب سورج ہمارے حصہ ملک کے سامنے ہوتا ہے خواہ اس کے سامنے بادل ہی
کیوں نہ آ گیا ہو.اور جب وہ ہمارے حصہ ملک کے سامنے نہ ہو تو خواہ اس کے آگے بادل نہ ہو
ہمارے ملک والے اس وقت کو دن نہیں کہیں گے اور یہ نہیں کہیں گے کہ سورج روشن ہے.پس نہار اور مفہوم پیدا کرتا ہے اور ضُحھا اور مفہوم پیدا کرتا ہے.ضُحى الشمس ہر وقت
قائم رہتی ہے خواہ سورج کسی حصہ دنیا کے سامنے ہو یا نہ ہو.کیونکہ وہ سورج کی ذاتی روشنی پر
دلالت کرتی ہے.اور بہار دنیا کے مختلف حصوں کے لحاظ سے بدلتا رہتا ہے.کبھی یہاں دن
کبھی وہاں.کیونکہ دن اس وقت کو کہتے ہیں جب زمین سورج کے سامنے ہو کر لوگوں کو اپنی
تھی دکھاتی ہے.وَالنَّهَارِ إِذَا جَلْهَا میں تو زمین کی اس حالت کا ذکر کیا تھا جب وہ سورج کے سامنے آکر آبادی
کو سورج دکھا دیتی ہے اور وَالَّيْلِ إِذَا يَغْشها میں زمین کی اس کیفیت کا ذکر کیا گیا ہے جب وہ
سورج سے اپنا منہ موڑ کر تیل پیدا کر دیتی اور دنیا کی نظروں سے سورج کو روپوش کر دیتی ہے.ان چار آیات میں چار الگ الگ زمانوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے.وَالشَّن و
خطها میں اللہ تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ ہم سورج کو
تمہارےسامنے بطور مثال پیش کرتے ہیں...جو اپنے اندر ذاتی روشنی رکھتا ہے اور جوظلمتوں کو
763
Page 772
دور کرنے کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے.اس کے بعد روشنی کا دوسراذ ریعہ چاند
ہوتا ہے اور وہ بھی ایسی حالت میں جب وہ سورج کے سامنے آجاتا ہے اس وقت وہ بھی دنیا کو اپنی
شعاعوں سے منور کر دیتا ہے.یہ دوز رائع ہیں جو دنیا میں انتشار نور کے لئے کام آتے ہیں.وَالشَّمْسِ وَضُعَهَا میں بتایا کہ رسول کریم ملایان علی والے وجود ہیں.چاہے تم اس نور
سے فائدہ اٹھا دیا نہ اٹھاؤ ان کا تو نور بہر حال ظاہر ہوتا چلا جائے گا یہاں تک کہ دنیا ایک دن
تسلیم کرے گی کہ آپ حقیقت میں روحانی سورج تھے.پس دنیا ان کے سامنے آئے یا نہ آئے
اس کا کوئی سوال نہیں.دنیا اس شمس کے سامنے آئے گی تو منور ہو جائے گی اور اگر نہ آئے گی تو
ی شمس بہر حال شمس ہے اس کی ضحی پر اس بات کا کوئی اثر نہیں ہوسکتا کہ لوگوں نے اس کی
طرف سے اپنی پیٹھ موڑ لی ہے.پھر فرمایا ہے وَالْقَمَرِ إِذَا تلها یعنی آپ کے بعد بعض اور وجود بھی آئیں گے جو قمر کی
حیثیت رکھیں گے یعنی محمد رسول الله عالی یہ نہ صرف ایسے شمس ہیں جو اپنی ذات میں روشن اور
پُرانوار ہیں بلکہ خدا تعالیٰ نے آپ کے نور سے اکتساب کرنے کے لئے بعض قمر بھی پیدا کر
دیتے ہیں جو ہر زمانہ میں ان کے نور کو دنیا میں پھیلاتے رہیں گے.وَالنَّهَارِ إِذَا جَلْهَا میں بتایا کہ ہمارا یہ سورج صرف اپنی ذات میں ہی روشنی نہیں رکھتا
بلکہ ایک زمانہ آئے گا جبکہ دنیا بھی اس سے روشنی لے لے گی.اس جگہ نہار سے مرادزمانہ نبوی
نہیں بلکہ نہار سے مراد بعد کا زمانہ ہے جب سورج تو نہ ہوگا مگر دن کا وقت سورج کولوگوں کی
آنکھوں کے سامنے لاتا رہے گا یہاں تک کہ رات آجائے گی اور وہ اسے ڈھانپ لے گی اور
ایک بار دنیا پھر معلوم کرلے گی کہ سورج کے بغیر گزارہ نہیں اور اس سے ڈوری خسران و تباب کا
موجب ہے.اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جسمانی اور روحانی سورج میں ایک فرق بتایا ہے.جسمانی سورج تو جب تک موجود رہتا ہے دن چڑھا رہتا ہے اور جب وہ نظروں سے اوجھل ہو
جاتا ہے رات آجاتی ہے لیکن روحانی سورج کی روشنی اس کے غائب ہونے کے بعد بڑھنی
شروع ہوتی ہے گویا دنیوی دن تو سورج کے ہوتے ہوئے چڑھتا ہے لیکن روحانی دن سورج
764
Page 773
کے غائب ہونے کے بعد اپنے کمال کو پہنچتا ہے.ا وَالَّيْلِ إِذَا يَغْشها پھر فرماتا ہے تیری امت پر ایک وہ زمانہ بھی آنے والا ہے جب
سورج سے وہ اپنا منہ موڑلے گی اور نہار کی بجائے لیل کا زمانہ اس پر آجائے گا....چنانچہ
جب رات اُن پر چھا جائے گی اور دنیا بزبان حال ایک سورج کا مطالبہ کر رہی ہوگی اللہ تعالیٰ
پھر ایک چاند کو جو سورج کا قائم مقام ہوتا ہے چڑھا دے گا اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے
روشنی لے کر اسے ساری دنیا میں پھیلا دے گا.غرض اللہ تعالیٰ نے وَالشَّمْسِ وَضُهَا.وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَهَا میں اس حقیقت کو بیان فرمایا
ہے کہ بعض انفاس اپنے اندر ذاتی فضیلت رکھتے ہیں اور وہ دنیا کو چمکا دیتے ہیں.اور دراصل
ایسے ہی وجود دنیا کی اصلاح کی قوت اپنے اندر رکھتے ہیں.اس کے بالمقابل بعض انفاس قمر کی
حالت رکھتے ہیں اور اُسی وقت دنیا کی ہدایت کا موجب ہوتے ہیں جب وہ سورج کے پیچھے
آتے ہیں یعنی اُن کا نور ذاتی نہیں بلکہ مکتسب ہوتا ہے.ان دونوں حالتوں کو اللہ تعالیٰ نے
بطور شاہد پیش کیا ہے اور بتایا ہے کہ اصلاح عالم بغیر ان دو قسم کے وجودوں کے نہیں ہو سکتی یا
نفس کامل یا متبع کامل - نفس کامل وہ ہے جس کا ذکر و الشَّمْسِ وَضُحَھا میں آتا ہے.اور متبع
کامل وہ ہے جس کا ذکر وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَهَا میں آتا ہے.جب تک ان دونوں صفات میں سے
کوئی ایک صفت موجود نہ ہو کوئی شخص اصلاح کا فرض سر انجام نہیں دے سکتا.وَالسَّمَاء وَمَا بَنهَا ہم شہادت کے طور پر آسمان کو پیش کرتے ہیں اور اسے بھی جس
نے اسے بنایا.آیت کے یہ معنی ہوں گے کہ ہم آسمان اور اُسے بنانے کی یعنی خدا تعالیٰ کی صنعت کی
شہادت تمہارے سامنے پیش کرتے ہیں اس صورت میں بھی شہادت تو خدا تعالیٰ کے فعل کی
ہی ہوگی مگر براہ راست آسمان کی بناوٹ کو پیش کرنا سمجھا جائے گا.اسی طرح وَالْأَرْضِ وَمَا ظلها..کے یہ معنے ہوں گے کہ ہم شہادت کے طور پر زمین
کو پیش کرتے ہیں اور اس کے بچھے ہوئے ہونے کو بھی.765
Page 774
بہت سے سیارے ایسے ہیں جو ر ہائش کے قابل نہیں اسی طرح بعض زمینیں ایسی ہیں جو
انسانی رہائش کے قابل نہیں ہوتیں....زمین کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کے قابل رہائش
ہونے کا ذکر اس لئے کیا ہے کہ بعض زمینیں ایسی ہیں جو انسانی رہائش کے قابل نہیں ہیں.چنانچہ وَالْأَرْضِ وَمَا طَحها میں اللہ تعالیٰ اسی صنعت کی طرف اشارہ کرتا ہے اور بتا تا ہے کہ کیا
تم دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالی نے زمین کو تمہاری رہائش کے قابل بنایا ہے اور یہ اس کا ایک
بہت بڑا احسان ہے جس سے اس نے تمہیں نوازا.یہ امر یاد رکھنا چاہئے کہ قرآن کریم میں آسمان سے مراد صرف جو نہیں ہوتا بلکہ تمام
ستارے، سیارے اور روشنیاں وغیرہ اس سے مراد ہوتی ہیں.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس طرح ان
کے بغیر زمین کام نہیں دے سکتی اسی طرح محمد رسول اللہ علیم کے بغیر تم بھی کوئی خوبی ظاہر
نہیں کر سکتے.اور پھر جس طرح آسمانی فیوض سے زمین انکار نہیں کر سکتی اسی طرح محمد رسول اللہ
ام کے روحانی فیوض سے بھی تم ہمیشہ کے لئے انکار نہیں کر سکتے.اگر زمین کے سامنے سورج
آئے تو کیا زمین اس وقت کہ سکتی ہے کہ میں روشنی نہیں لیتی.وہ مجبور ہے کہ سورج سے روشنی
حاصل کرے.اسی طرح جب محمد رسول اللہ علیہ ظاہر ہو گئے ہیں تو اب دنیا آپ کا زیادہ دیر
تک انکار نہیں کر سکے گی وہ ضرور آپ پر ایمان لائے گی.وَنَفْسٍ وَمَا سَوهَا
اور انسانی نفس کی اور اس کے بے عیب بنائے جانے کی.سوی کے معنے معتدل القویٰ کے بنانے کے ہوتے ہیں....جس طرح پہلی آیت
میں بتایا تھا کہ ہم نے زمین کو قابل رہائش بنایا اسی طرح یہاں یہ بھی بتایا ہے کہ ہم نے نفس کا
تسو یہ کیا اور اس میں ایسی قوت پیدا کی ہے کہ وہ اعتدال سے ترقی کی طرف جاتا ہے.اللہ تعالیٰ
فرماتا ہے اگر تمہارے نفس میں یہ شہادت موجود نہ ہوتی اور جس طرح ہم نے زمین کو طحی کیا
ہے اس طرح تمہارے نفوس کا تسویہ نہ کیا ہوتا تو تم کہہ سکتے تھے کہ ہم پر یہ مثال چسپاں نہیں ہو
سکتی.لیکن جب نفوس انسانی میں اعتدال کو اختیار کر کے ترقی کرنے کا مادہ پایا جاتا ہے تو تم یہ
766
Page 775
نہیں کہہ سکتے نفس انسانی خود اس امر پر شاہد ہے کہ کوئی نور اسے آسمان سے ملنا چاہئے جس
طرح زمین آسمانی روشنی کی محتاج ہوتی ہے اسی طرح تم آسمانی نور کے محتاج ہو.غرض انسان کو ایک معتدل القویٰ نفس عطا کیا گیا ہے اس میں ترقی کا مادہ ہے جو اعلیٰ
درجہ کے مقصود تک پہنچنے کے لئے ہے.پھر اس میں اپنے دائیں اور بائیں کو محفوظ رکھنے کا مادہ
ہے جس سے اخلاق کی تکمیل ہوتی ہے.وہ جانتا ہے کہ فلاں کام مجھے کرنا چاہئے اور فلاں نہیں.فلاں کام میرے لئے مفید ہے اور فلاں مضر.جب انسان کے اندر یہ تمام قابلیتیں پائی جاتی
ہیں تو تم کسی راہنما اور معلم کا کیونکر انکار کر سکتے ہو؟
فَالْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقُوهَا
پھر اس ( یعنی خدا) نے اس (نفس) پر اس کی بدکاری ( کی راہوں) اور اس کے تقویٰ
( کے راستوں ) کو کھول دیا.یاد رکھنا چاہئے کہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے سمجھنے میں بہت سے لوگ غلطی کھا
جاتے ہیں اور وہ بجائے مسئلہ کو اس رنگ میں پیش کرنے کے کہ ہر انسان کچھ باتوں کو اچھا
سمجھتا اور کچھ باتوں کو برا سمجھتا ہے وہ اس رنگ میں بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہر انسان
سمجھتا ہے کہ قتل برا ہے.یا ہر انسان سمجھتا ہے کہ جھوٹ بولنا بُرا ہے.یا ہر انسان سمجھتا ہے کہ
ڈاکہ ڈالنا بُرا ہے.اس پر اس کے مخالف جواب دے دیتے ہیں کہ تم کہتے ہو ہر شخص جھوٹ کو
بُراسمجھتا ہے حالانکہ دنیا میں کئی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جھوٹ کے بغیر گزارہ
ہی نہیں ہوسکتا.اگر تمہاری یہ بات درست ہے کہ فجور اور تقویٰ کا الہام اللہ تعالیٰ نے نفس انسانی
میں کیا ہے تو چاہئے تھا کہ ہر شخص جھوٹ کو بر آسمجھتا یا ہر شخص قتل کو برا سمجھتا.مگر واقعہ یہ ہے کہ
بہت سے لوگ دنیا میں جھوٹ بولتے ہیں اور چونکہ ان کے نفس میں ہدایت نہیں ہوتی اور متواتر
جھوٹ بول بول کر ان کی فطرت مسخ ہو چکی ہوتی ہے وہ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ جھوٹ کے
بغیر دنیا میں گزارہ ہی نہیں ہوسکتا.اسی طرح بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو چوری کو برا نہیں سمجھتے ، بعض لوگ ایسے
767
Page 776
ہوتے ہیں جو جھوٹ کو برانہیں سمجھتے ، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قتل کو برا نہیں سمجھتے.پس
اگر اس کے یہ معنے لئے جائیں کہ ہر انسان چوری کو یا جھوٹ کو یا قتل وغیرہ جرائم کے ارتکاب
کو برا سمجھتا ہے تو یہ بالکل غلط ہو گا.دنیا میں کئی لوگ ایسے ہیں جو ان افعال کو برا نہیں
سمجھتے....کوئی انسان دنیا میں ایسا نہیں ہو سکتا جو ہر چیز کو اچھا کہتا ہو یا ہر چیز کو برا سمجھتا ہو.ہر
انسان یہی کہے گا کہ بُرا کام نہیں کرنا چاہئے اور ہر انسان یہی کہے گا کہ اچھا کام ضرور کرنا
چاہئے.یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ بُرے کام کو اچھا سمجھتا ہو یا اچھے کام کو بُرا سمجھتا ہومگر یہ احساس
اس کے اندر ضرور پایا جاتا ہے کہ دنیا میں کچھ چیزیں اچھی ہیں اور کچھ چیزیں بُری ہیں.مجھے
اچھی چیزیں اختیار کرنی چاہئیں اور بُری چیزوں سے اجتناب کرنا چاہئے.یہی معنے فَالْهَمَهَا
فُجُورَهَا وَتَقُوهَا کے ہیں کہ ہر انسان یہ کہتا ہے کہ کچھ بُری چیزیں ہیں اور ہر انسان یہ کہتا ہے
کہ کچھ اچھی چیزیں ہیں.جس کے معنے یہ ہیں کہ ہر انسان میں اچھی اور بری چیزوں کے امتیا ز کا
مادہ رکھا گیا ہے اور جب یہ بات ہے تو دلیل مکمل ہو جاتی ہے.یعنی جب ہر انسان کے اندر یہ
مادہ پایا جاتا ہے کہ وہ کسی چیز کو اچھا اور کسی چیز کو برا کہتا ہے تو ضروری ہے کہ کوئی ایسی ہستی
بھی ہو جو اسے بتائے کہ کون کون سی چیزیں اچھی ہیں اور کون کون سی چیزیں بُری ہیں.یہ
دلیل ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی ہستی کے ثبوت میں لوگوں کے سامنے پیش کی ہے اور یہ دلیل
ہے جس کا کوئی رد کسی بڑے سے بڑے دہریہ کے پاس بھی نہیں ہے.اللہ تعالیٰ نے صرف یہ فرمایا ہے کہ ہم نے اسے فجور اور تقویٰ کا الہام کیا ہے یعنی ہر انسان
میں فجور اور تقویٰ کی حس پائی جاتی ہے اور ہر انسان میں اللہ تعالیٰ نے ایسا مادہ رکھا ہے کہ وہ اس
بات کو خوب
سمجھتا ہے کہ میرے نفس کے لئے کچھ باتیں اچھی ہیں اور کچھ بری ہیں.قد أفلح من زكهَا
جس نے اس (نفس) کو پاک کیا.وہ تو سمجھو کہ ) اپنے مقصود کو پا گیا.768
Page 777
فرماتا ہے اس الہام کے بعد جو شخص اس کی پیروی کر کے اپنے نفس کو ٹھیک راہ پر
چلاتا ہے وہ بامراد ہو جاتا ہے یعنی الہام فطرت جو مجمل الہام ہوتا ہے اس کی پیروی اور اطاعت
کا یہاں ذکر کیا گیا ہے.یہ امر یا درکھنا چاہئے کہ نبی کا الہام تفصیلی ہوتا ہے لیکن فطرت کا الہام
مجمل ہوتا ہے.یہاں تفصیلی الہام کا ذکر نہیں بلکہ مجمل الہام کا ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ
فجور اور تقویٰ کا وہ مجمل علم جو انسان کو ملا تھا اور جس کے مطابق وہ سمجھتا تھا کہ دنیا میں کچھ بری
چیزیں ہیں اور کچھ اچھی چیزیں ہیں، مجھے بری چیزوں سے بچنا چاہئے اور اچھی چیزوں کو اختیار
کرنا چاہئے.جو شخص اس مجمل علم کو صحیح طور پر استعمال کرتا ہے اور فطرت کی اس راہنمائی کے
ماتحت اپنے نفس کو اونچا کرتا ہے وہ فلاح پالیتا ہے یعنی اپنے خدا سے واصل ہو کر صاحب الہام
ہو جا تا ہے.ان معنوں کے لحاظ سے قد أفلح میں وحی حقیقی کے پانے کا ذکر ہے اور الْهَمَهَا
میں وحی مجمل کے نازل ہونے کا بیان ہے جو ہر فطرت انسانی پر نازل ہوتی ہے.رسٹی کے معنے اونچا کرنے کے بھی ہوتے ہیں اور ڈسٹی کے معنے پاک کرنے کے بھی
ہوتے ہیں.اس جگہ نفس کو اونچا کرنے کے معنے چسپاں ہوتے ہیں کیونکہ ایسا شخص فجور اور
تقویٰ کی حس سے کام لے کر فطرت کے مقام سے بلند ہو کر اخلاقی زندگی میں داخل ہو جاتا ہے
اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خود صاحب الہام ہو جاتا ہے.وَقَدْ خَابَ مَنْ دَشْهَا
اور جس نے اسے (مٹی میں گاڑ دیا ( سمجھو کہ ) وہ نامراد ہو گیا.حمد اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون بیان فرمایا ہے کہ جس نے اس وحی کو نہ مانا وہ
نا کام ہوا کیونکہ وحی الہی فطرت کی طاقتوں کو ابھارنے کے لئے آتی ہے جس نے اسے رد کر دیا
اُس نے اپنے نفس پر ظلم کیا اور اپنے آپ کو بلاک کر لیا.دوسرے مذاہب فطرت کی بعض طاقتوں کو کچلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ نیکی ہے مگر اسلام
اسے نیکی قرار نہیں دیتا.اسلام یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر جو قوتیں پیدا کی ہیں
769
Page 778
صرف ان
کا تسو یہ ہونا چاہئے اور ان کے استعمال میں اعتدال کو ملحوظ رکھنا چاہئے.وہ یہ نہیں کہتا
کہ فطرت کو مار دو بلکہ وہ کہتا ہے تم فطرت سے اونچا مقام حاصل کرنے کی کوشش کرو کیونکہ
فطرت کا علم ایک مجمل علم ہوتا ہے اور مجمل علم سے نجات نہیں ہوسکتی.پس قد فَلَحَ مَنْ زَكُهَا وَ قَدْ خَابَ مَنْ دَشَهَا کے یہ معنے ہوئے کہ اگر تم اپنی فطری
طاقتوں کو ابھارتے ہو تو الہی مدد کو حاصل کر لیتے ہو لیکن اگر تم ان طاقتوں کو دباتے ہو اور اس چیز
کو ضائع کر دیتے ہو جو تمہیں ہتھیار کے طور پر دی گئ تھی تو تم کبھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے.كَذَّبَت المود يطعوها
شمود نے اپنی حد سے بڑھی ہوئی سرکشی کی وجہ سے ( زمانے کے نبی کو ) جھٹلایا.حمد یہاں اللہ تعالیٰ نے دش کا طریق بتایا ہے کہ وہ دو ہی طرح ہو سکتا ہے یا تو جتنی قوت
انسان کے اندر موجود ہوتی ہے وہ اس سے آگے نکل جاتا ہے اور یا پھر جتنی قوت موجود ہوتی
ہے اس سے پیچھے رہ جاتا ہے.حد سے نکل جانا دونوں طرح ہی ہوتا ہے.اس طرح بھی کہ
انسان اگلی طرف کو چلا جائے اور اس طرح بھی کہ پچھلی طرف کو آجائے.ایسے کاموں سے
فطرت کا نور مارا جاتا ہے اور اس کی قوتیں کچلی جاتی ہیں.فرماتا ہے ثمود کی بھی یہی کیفیت تھی.وہ لوگ اپنے کاموں میں حد سے آگے نکل گئے تھے خدا تعالیٰ نے ایک وسطی تعلیم ان کے لئے
نازل کی تھی مگر وہ اس درمیانی خط پر کھڑے ہونے کی بجائے کبھی ادھر چلے جاتے اور کبھی
اُدھر چلے جاتے.درمیانی راستہ جو پل صراط ہوتا ہے اور جس پر ہر مومن کو اس دنیا میں چلنا پڑتا
ہے اُس راستہ پر وہ نہیں چلتے بلکہ یا دائیں طرف کو نکل جاتے تھے یا بائیں طرف کو نکل
جاتے.اعتدال کو انہوں نے ترک کر دیا تھا.إذا تبَعَتَ اَشْقُهَا.فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ نَاقَةَ اللهِ وَسُقُيهَا
یہ ایک نہایت لطیف مثال ہے مگر افسوس ہے کہ لوگوں نے اس کی حکمت کو نہیں سمجھا
اور انہوں نے خیال کر لیا ہے کہ وہ ناقہ اپنے اندر کوئی خاص عظمت اور شان رکھتی تھی جس کی
770
Page 779
کونچیں کاٹنے پر ثمود کی قوم اللہ تعالیٰ کے عذاب کا نشانہ بن گئی.اسی لئے بعض مفسرین نے
اس ناقہ کے متعلق یہ عجیب بات لکھ دی ہے کہ وہ پہاڑ سے پیدا ہوئی تھی عام اونٹنیوں کی طرح
نہیں تھی.حالانکہ نبی کی موجودگی میں یہ ہو ہی کس طرح سکتا تھا کہ نبی کو دکھ دینے کی وجہ سے تو
قوم پر عذاب نازل نہ ہو اور ناقہ کی کونچیں کاٹنے پر عذاب نازل ہو جائے!
اصل بات یہ ہے کہ حضرت صالح" عرب میں مبعوث ہوئے تھے اور عرب میں اونٹوں پر
سواری کی جاتی تھی.حضرت صالح بھی اپنی اونٹنی پر سوار ہوتے اور ادھر ادھر تبلیغ کے لئے نکل
جاتے.لوگ کھلے طور پر حضرت صالح" کا مقابلہ کرنے سے ڈرتے تھے کیونکہ ان کے رشتہ دار
موجود تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے صالح" کو کوئی تکلیف پہنچائی تو اس کے رشتہ دار ہم
سے بدلہ لینے کے لئے کھڑے ہو جائیں گے.مگر چونکہ وہ تبلیغ بھی پسند نہیں کرتے تھے اس لئے
وہ بعض اور طریق آپ کو دکھ پہنچانے کے لئے اختیار کر لیتے تھے.انہی میں سے ایک طریق یہ
تھا کہ جب حضرت صالح تبلیغ کے لئے ارد گرد کے علاقوں میں نکل جاتے تو کسی جگہ کے لوگ
کہتے کہ ہم ان کی اونٹنی کو پانی نہیں پلائیں گے، کسی جگہ کے لوگ کہتے کہ ہم کھانے کے لئے
کچھ نہیں دیں گے.ان کی غرض ی تھی کہ جب انہیں اونٹنی کے لئے پانی اور چارہ وغیرہ نہ ملا تو یہ
خود بخود اس قسم کے سفروں سے رک جائیں گے اور تبلیغ میں روک پیدا ہو جائے گی.حضرت صالح نے ان کو سمجھایا کہ تم اس ناقہ کو آزاد پھر نے دو اور اس کے پانی پینے میں روک
نہ بنو کیونکہ اس طرح میری تبلیغ میں روک واقعہ ہوجائے گی.یہ مطلب نہیں تھا کہ تم مجھے تو اپنے
پاس بے شک نہ آنے دو مگر یہ اونٹنی آئے تو اسے پانی پلا دینا.انہیں اونٹنی سے کوئی دشمنی
نہیں تھی.انہیں اگر دشمنی تھی تو حضرت صالح ہے.اور وہ کہتے تھے کہ وہ اونٹنی پر سوار ہو کر
ارد گرد کے علاقوں میں ایک شور پیدا کر دیتے ہیں اور انہیں اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کی
طرف تو جہ دلاتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہئے.یہ چیز تھی جو ان کی طبائع پر سخت گراں گزرتی تھی.اور آخر اس کا علاج انہوں نے یہ سوچا کہ جب حضرت صالح" باہر نکلتے تو ان کی اونٹنی کو وہ کہیں
پانی نہ پینے دیتے.اس پر حضرت صالح علیہ السلام نے اظہار ناراضگی کرتے ہوئے کہا ناقةً
771
Page 780
اللهِ وَسُقيها کہ یہ طریق درست نہیں تم میری اس ناقہ کو آزاد پھر نے دو اور اس کے پانی میں
روک نہ بنو.یعنی تم مختلف ذرائع سے میری تبلیغ میں روک بن رہے ہو اپنے اس طریق کو چھوڑو
اور مجھے آزاد پھر نے دو تا کہ میں خدا تعالیٰ کا پیغام سب لوگوں تک پہنچا تار ہوں....جب حضرت صالح نے ان سے کہا کہ میری اس ناقہ کو چھوڑ دو تو ان کا یہ مطلب نہیں تھا کہ
میرے ساتھ تو جیسا چاہوسلوک کرو مگر اس ناقہ کو کچھ نہ کہو بلکہ ان کا مطلب یہ تھا کہ تم میری تبلیغ
میں روک مت بنو.اگر تم اسی طرح میری اونٹنی کو پانی پینے سے روکتے رہے تو میری تبلیغ رک
جائے گی اور علاقوں کے علاقے ہدایت پانے سے محروم رہ جائیں گے.فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا
حضرت صالح کے سمجھانے کے باوجود ثمود نے ان کی بات کی طرف کوئی توجہ نہ کی.انہوں نے اسے جھٹلایا اور ناقہ کی کونچیں کاٹ دیں یعنی اپنے ارادوں کا انہوں نے علی الاعلان
اظہار کردیا اور کہہ دیا کہ تم خواہ کچھ کہو ہم تمہیں تبلیغ نہیں کرنے دیں گے.فَدَمُدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوهَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَهَا
فرماتا ہے چونکہ انہوں نے ہمارے رسول کی بات نہ مانی اس لئے ہم نے ان پر عذاب
نازل کیا اور عذاب بھی ایسا سخت که فَسَوهَا خدا نے انہیں زمین کے ساتھ ملا دیا اور ان کے
چھوٹوں اور بڑوں کو اس طرح تباہ کیا کہ ان کا نشان تک دنیا میں نہ رہا.قرآن کریم اپنے کلام میں کیسی بلاغت کی شان رکھتا ہے کہ پہلے فرمایا تھا وَ نَفْسٍ وَمَا
سوما ہم نے انسان کو معتدل القویٰ بنایا ہے اور خود انسانی نفس اس امر پر شاہد ہے کہ اسے کوئی
نور آسمان سے ملنا چاہئے.اب فرماتا ہے چونکہ انہوں نے اس تشویہ کی قدر نہ کی اور ہمارے
احکام کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اس لئے ہم نے ان کا دوسری طرح تشویہ کر دیا کہ ان کا
نشان تک دنیا سے مٹا دیا.یہ بلاغت کا کمال ہے کہ جس چیز کا انہوں نے انکار کیا تھا عذاب
کے معنوں میں بھی وہی لفظ لے آیا.انہوں نے تسویہ نفس سے انکار کیا تھا اللہ تعالیٰ نے وہی لفظ
اس جگہ استعمال کر دیا اور فرمایا کہ چونکہ انہوں نے تشویہ سے انکار کیا تھا، ہم نے ان کا اس
772
Page 781
رنگ میں تشویہ کر دیا کہ ان کا ملک تباہ کر دیا.ان کی عمارتیں گرگئیں.قوم بلاک ہوگئی اور اتنا
بڑا زلزلہ آیا کہ ان کا نشان تک باقی نہ رہا.عقب میں تھا کی ضمیر تقدمة کی طرف جاتی ہے اور آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب
دَمُدَمَة نازل کرنے کا وقت آتا ہے اور کوئی قوم گلی بلاکت کی مستحق ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ
یہ نہیں دیکھتا کہ ان کے متعلقین کا کیا حال ہوگا یا یہ کہ اس سزا کا نتیجہ کیسا خطرناک نکلے گا.بعض
دفعه ساری قوم بلاک نہیں ہوتی بلکہ اس کا کچھ حصہ بچ رہتا ہے جو دنیا میں انتہا طور پر ذلیل ہو جاتا
ہے.مگر فرماتا ہے جب ہماری طرف سے کسی قوم کو تباہ کرنے کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر ہم اس
بات کی پروا نہیں کرتے کہ اس قوم کے بقیہ افراد کیا کیا تکالیف اٹھائیں گے.جب قوم کی
اکثریت خدا تعالیٰ کے غضب کی مستحق ہو جاتی ہے اور خاموش رہنے والے گو مقابلہ نہیں کرتے مگر
نبی کی تائید بھی نہیں کرتے تو وہ بھی اکثریت کے ساتھ ہی تباہ و برباد کر دئیے جاتے ہیں.اس سے
یہ مراد نہیں کہ اللہ تعالی ظلم کرتا ہے یا اندھا دھند عذاب نازل کر دیتا ہے بلکہ جس قوم کے
استیصال کا وہ فیصلہ کرتا ہے انصاف کے ماتحت کرتا ہے اور جب کہ وہ خود اپنے انجام کو نہیں
دیکھتی تو اللہ تعالیٰ اس کے انجام کو کیوں دیکھے.(ماخوذ از تفسیر کبیر)
773
Page 783
XXXXXXXX
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
والصحية
وَالَّيْلِ إِذَا سَجُي 3
مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى
وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولى
وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضُى
أَلَمْ يَجِدُكَ يَتِيمَا فَاوِيةٌ
وَوَجَدَكَ ضَا لَّا فَهَدَى
سورة الضحى
1 - (میں) اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا
( اور ) بار بار رحم کرنے والا ہے ( پڑھتا ہوں)
2.میں دن کو شہادت کے طور پر پیش کرتا ہوں جب وہ
روشن ہو جائے.3.اور رات کو ( شہادت کے طور پر پیش کرتا ہوں )
جب اس کی تاریکی چاروں طرف پھیل جائے.4.کہ نہ تیرے رب نے تجھے ترک کیا ہے اور نہ
تجھ سے ناراض ہوا ہے.5.اور ( دیکھ تو سہی کہ) تیری ہر پیچھے آنے والی
گھڑی پہلی سے بہتر ہوتی ہے.6.اور ضرور تیرا رب تجھے ( وہ کچھ ) دے کر رہے گا
جس پر تو خوش ہو جائے گا.7.کیا ( اس زندگی میں اس کا سلوک غیرے ساتھ
غیر معمولی نہیں رہا اور ) اس نے مجھے یتیم پا کر ( اپنے
زیر سایہ ) جگہ نہیں دی.8.اور ( جب ) اس نے تجھے (اپنی قوم کی محبت
میں ) سرشار دیکھا تو ( ان کی اصلاح کا ) صحیح راستہ
تجھے بتا دیا.وَوَجَدَكَ عَابِلًا فَاغْنى
9.اور جب تجھے کثیر العیال پایا تو اپنے فضل سے)
غنی کر دیا.فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرُة
10.پس ان احسانوں کے نتیجہ میں) تو بھی
یتیموں کو ابھارنے میں لگارہ.775
Page 784
وَأَمَّا السَّابِلَ فَلَا تَنْهَرْهُ
وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثُ ن
776
11.اور سوالی کو تو جھڑک مت.12.اور تو اپنے رب کی نعمت کا ضرور ا ظہار کرتارہ.
Page 785
حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں:
یہاں جو ٹھٹھی اور تیل کی قسم کھائی اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدارج عالیہ
اور مراتب محبت کا اظہار ہے اور آگے پیغمبر خدا کا ابراء کیا کہ دیکھو دن اور رات جو بنائے ہیں
ان میں کس قدر وقفہ ایک دوسرے میں ڈال دیا ہے صیحی کا وقت بھی دیکھو اور تاریکی کا وقت بھی
خیال کرو.مَا وَذَعَكَ رَبُّكَ - خدا تعالیٰ نے تجھے رخصت نہیں کر دیا.اس نے تجھ سے کینہ نہیں
کیا بلکہ ہمارا یہ ایک قانون ہے جیسے رات اور دن کو بنایا ہے اسی طرح انبیاء علیہم السلام کے
ساتھ بھی ایک قانون ہے کہ بعض وقت وحی کو بند کر دیا جاتا ہے تا کہ ان میں دعاؤں کے لئے
زیادہ جوش پیدا ہو.اور ضحی اور تیل کو اس لئے بطور شاہد بیان فرمایا تا آپ کی امید وسیع ہو اور
66
تسلی اور اطمینان پیدا ہو.“
(الحکم جلد 5 نمبر 21 مورخہ 10 جون 1901 ، صفحہ 4 واحکم جلد 5 نمبر 22 مورخہ 17 جون 1901 ، صفحہ 1)
اوی کا لفظ زبان عرب میں ایسے موقع پر استعمال ہوتا ہے کہ جب کسی شخص کو کسی قدر
مصیبت یا ابتلا کے بعد اپنی پناہ میں لیا جائے اور کثرتِ مصائب اور تلف ہونے سے بچایا
جائے.جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَلَمْ يَجِدُكَ يَتيما فاوی.اسی طرح تمام قرآن شریف
میں اوی اور آؤی کا لفظ ایسے ہی موقعوں پر استعمال ہوا ہے کہ جہاں کسی شخص یا کسی قوم کو کسی
قدر تکالیف کے بعد پھر آرام دیا گیا.( تذکرۃ الشہادتین، روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 9 حاشیہ)
جو شخص قرآن کریم کی اسالیب کلام کو بخوبی جانتا ہے اس پر یہ پوشیدہ نہیں کہ بعض
اوقات وہ کریم ورحیم جل شانہ اپنے خواص عباد کے لئے ایسا لفظ استعمال کر دیتا ہے کہ بظاہر بدنما
ہوتا ہے مگر معناً نہایت محمود اور تعریف کا کلمہ ہوتا ہے جیسا کہ اللہ جل شانہ نے اپنے نبی کریم
کے حق میں فرمایا وَ وَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَی اب ظاہر ہے کہ ضال کے معنے مشہور اور متعارف
777
Page 786
جو اہل لغت کے منہ پر چڑھے ہوئے ہیں گمراہ کے ہیں جس کے اعتبار سے آیت کے یہ معنی
ہوتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے (اے رسول اللہ ) تجھ کو گمراہ پایا اور ہدایت دی.حالانکہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی گمراہ نہیں ہوئے اور جو شخص مسلمان ہو کر یہ اعتقادر کھے کہ کبھی
آنحضرت صلعم نے اپنی عمر میں ضلالت کا عمل کیا تھا تو وہ کافر بے دین اور حد شرعی کے لائق
ہے.بلکہ آیت کے اس جگہ وہ معنی لینے چاہئے جو آیت کے سیاق اور سباق سے ملتے ہیں اور وہ
یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے پہلے آنحضرت صلعم کی نسبت فرمایا أَلَمْ يَجِدُكَ يَتِيَّا فَأَوَى وَوَجَدَكَ
ضَأَلَّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْلى یعنی خدا تعالیٰ نے تجھے یتیم اور بیکس پایا اور اپنے پاس
جگہ دی اور تجھ کو منال ( یعنی عاشق وجہ اللہ ) پایا پس اپنی طرف کھینچ لایا اور تجھے درویش پایا پس
غنی کر دیا.ان معنوں کی صحت پر یہ ذیل کی آیتیں قرینہ ہیں جو ان کے بعد آتی ہیں یعنی یہ کہ
فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرُ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهرُ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبَّكَ فَحَيثُ - کیونکہ یہ تمام
آیتیں لف نشر مرتب کے طور پر ہیں اور پہلی آیتوں میں جو مدعا مخفی ہے دوسری آیتیں اس کی
تفصیل اور تصریح کرتی ہیں مثلاً پہلے فرمایا أَلم يَجِدُكَ يَتِيما فاوی اس کے مقابل پر یہ
فرمايا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ یعنی یاد کر کہ تو بھی یتیم تھا اور ہم نے تجھ کو پناہ دی ایسا ہی تو بھی
یتیموں کو پناہ دے.پھر بعد اس آیت کے فرمایا وَ وَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَی اس کے مقابل پر یہ
فرمایا وَأَما السَّائِلَ فَلا تنهر یعنی یاد کر کہ تو بھی ہمارے وصال اور جمال کا سائل اور ہمارے
حقائق اور معارف کا طالب تھا سو جیسا کہ ہم نے باپ کی جگہ ہو کر تیری جسمانی پرورش کی ایسا ہی
ہم نے استاد کی جگہ ہو کر تمام دروازے علوم کے تجھ پر کھول دیئے اور اپنے لقا کا شربت سب
سے زیادہ عطا فرمایا اور جو تو نے مانگا سب ہم نے تجھ کو دیا سوتو بھی مانگنے والوں کو ر دمت کر اور
ان کومت جھڑک اور یاد کر کہ تو عائل تھا اور تیری معیشت کے ظاہری اسباب بکلی منقطع تھے سو
خدا خود تیرا متوئی ہوا اور غیروں کی طرف حاجت لے جانے سے تجھے غنی کر دیا.نہ تو والد کا محتاج
ہوا نہ والدہ کا نہ استاد کا اور نہ کسی غیر کی طرف حاجت لے جانے کا بلکہ یہ سارے کام تیرے خدا
778
Page 787
تعالیٰ نے آپ ہی کر دئیے اور پیدا ہوتے ہی اس نے تجھ کو آپ سنبھال لیا.سواس کا شکر بجالا
اور حاجت مندوں سے تو بھی ایسا ہی معاملہ کر.اب ان تمام آیات کا مقابلہ کر کے صاف طور پر
کھلتا ہے کہ اس جگہ ضال کے معنے گمراہ نہیں ہے بلکہ انتہائی درجہ کے تعشق کی طرف اشارہ
ہے جیسا کہ حضرت یعقوب کی نسبت اسی کے مناسب یہ آیت ہے إِنَّكَ لَفِي ضَلَلِكَ
الْقَدِيمِ (یوسف 96) سو یہ دونوں لفظ ظلم اور ضلالت اگر چہ ان معنوں پر بھی آتے ہیں کہ کوئی
شخص جادہ اعتدال اور انصاف کو چھوڑ کر اپنے شہوات غضبیہ یا بہیمیہ کا تابع ہو جاوے.لیکن
قرآن کریم میں عشاق کے حق میں بھی آئے ہیں جو خدا تعالیٰ کے راہ میں عشق کی مستی میں اپنے
نفس اور اس کے جذبات کو پیروں کے نیچے کچل دیتے ہیں.( آئینہ کمالات اسلام، روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 170 تا 173)
قرآن شریف میں وَ اَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهرُ کا ارشاد آیا ہے کہ سائل کو مت جھڑک.اس میں یہ کوئی صراحت نہیں کی گئی کہ فلاں قسم کے سائل کومت جھڑک اور فلاں قسم کے سائل
کو جھڑک.پس یاد رکھو کہ سائل کو نہ جھڑ کو کیونکہ اس سے ایک قسم کی بداخلاقی کا بیج بویا جاتا
ہے.اخلاق یہی چاہتا ہے کہ سائل پر جلدی ناراض نہ ہو.یہ شیطان کی خواہش ہے کہ وہ اس
طریق سے تم کو نیکی سے محروم رکھے اور بدی کا وارث بناوے.الحکم جلد 4 نمبر 25 مورخہ 19 جولائی 1900 ، صفحہ 2)
عجز و نیاز اور انکسار...ضروری شرط عبودیت کی ہے لیکن بحکم آیت کریمہ و أما بِنِعْمَةِ
ربك فحيث نعماء الہی کا اظہار بھی از بس ضروری ہے.( مکتوبات احمد جلد دوم صفحہ 66)
حمد انسان کو چاہئے کہ ہر وقت اور ہر حالت میں دعا کا طالب رہے اور دوسرے آئما
بِنِعْمَةِ رَبَّكَ فَحَيّت پر عمل کرے.خدا تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کی تحدیث کرنی چاہئے.اس
سے خدا تعالیٰ کی محبت بڑھتی ہے اور اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کے لئے ایک جوش پیدا
ہوتا ہے.تحدیث کے یہی معنے نہیں ہیں کہ انسان صرف زبان سے ذکر کرتار ہے بلکہ جسم پر بھی
779
Page 788
اس کا اثر ہونا چاہئے.مثلاً ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ وہ عمدہ کپڑے پہن سکتا
ہے لیکن وہ ہمیشہ میلے کچیلے کپڑے پہنتا ہے اس خیال سے کہ وہ واجب الرحم سمجھا جاوے یا اس
کی آسودہ حالی کا حال کسی پر ظاہر نہ ہو ایسا شخص گناہ کرتا ہے کیونکہ وہ خدا تعالیٰ کے فضل اور کرم
کو چھپانا چاہتا ہے اور نفاق سے کام لیتا ہے.دھوکہ دیتا ہے اور مغالطہ میں ڈالنا چاہتا ہے یہ
مومن کی شان سے بعید ہے.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب مشترک تھا.آپ عالم کو
جو ملتا تھا پہن لیتے تھے.اعراض نہ کرتے تھے.جو کپڑا پیش کیا جاوے اسے قبول کر لیتے تھے
لیکن آپ میلم کے بعد بعض لوگوں نے اسی میں تواضع دیکھی کہ رہبانیت کی جز و ملادی.الحکم جلد 7 نمبر 13 مورخہ 10 اپریل 1903 صفحہ 1)
حضرت خلیفہ المسیح الثانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:
یہ سورۃ مکہ میں نازل ہوئی تھی.سورۃ انیل کے مضمون
کا یہ تمہ ہے.تھوڑ اسا دن نکل چکے تو اس وقت سے ضحی شروع ہوتی ہے اور زوال تک جاتی ہے.سجی کے معنے ہیں جب اندھیرا ترقی کرتے کرتے اپنے کمال کو پہنچ جائے.رسول کریم عالم کی زندگی میں ایک ضحی اور ایک لیل خصوصیت رکھتی ہیں.ضُھی
وہ دو پہر ہے جبکہ آپ مکہ کو فتح کر کے اس میں داخل ہوئے تھے اور وَالَّيْلِ إِذا سمجھی سے مراد
وہ رات ہے جب کہ آپ نے مکہ کو چھوڑا تھا.گویا والضُّحیٰ کے معنے ہوئے ایک خصوصیت
رکھنے والا دن.اور وَالَّيْلِ إِذَا سَنجی کے معنے ہوئے ایک خصوصیت رکھنے والی رات.اور
در حقیقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بڑے واقعات اگر کوئی خلاصہ پوچھے تو
یہی دو ہیں.دشمنوں نے آپ کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا.پھر خدا تعالیٰ نے اپنے خاص نشانات
سے دشمنوں کو تباہ کر کے آپ کو ایک فاتح کی حیثیت میں مکہ میں داخل فرمایا.انہی دو واقعات
کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم تیری سچائی کی شہادت کے طور پر یا اگلے
مضمون کی سچائی کو واضح کرنے کے لئے ایک ضحی کو پیش کرتے ہیں اور ایک ایسی رات کو
780
Page 789
پیش کرتے ہیں جو تاریکی سے اپنے ارد گرد کی تمام چیزوں کو ڈھانپ لے گی.ممکن ہے کوئی کہے کہ
یہاں ضحی پہلے ہے اور رات پیچھے حالانکہ فتح مکہ بعد میں ہوئی ہے اور ہجرت پہلی ہوئی ہے.اس کی وجہ...یہ ہے کہ الہی سنت یہ ہے کہ وہ اپنے پیاروں سے بات کرتے ہوئے خوشی
کی خبر پہلے سناتا ہے اور تکلیف کا ذکر بعد میں کرتا ہے تا کہ خوشی کی خبر رنج کی گلفت کو کم کرنے
کا موجب بن جائے.اس طرح دونوں مطلب پورے ہو جاتے ہیں.غم کی خبر بھی سنا دی جاتی
ہے اور خوشی کی خبر بھی سنادی جاتی ہے مگر چونکہ پہلے خوشی کی خبر آجاتی ہے اس لئے تکلیف کا
احساس نسبتاً کم ہو جاتا ہے.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ دو محل اس بات کو ثابت کر دیں گے کہ مَا وَذَعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلی
تیرے رب نے تجھے نہیں چھوڑا اور وہ تجھ سے ناراض نہیں ہوا.اور چونکہ وہ غرض جو وَالضُّحیٰ
پہلے رکھنے کی تھی پوری ہو گئی تھی یعنی غرض یہ تھی کہ رسول کریم عالم کو اس بات سے صدمہ نہ
پہنچے کہ تجھے ہجرت کرنی پڑے گی.اسی بناء پر خدا تعالیٰ نے رات کا ذکر پیچھے کردیا اور دن کا ذکر
پہلے رکھا.مگر چونکہ اس آیت سے غرض پوری ہوگئی اس لئے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ترتیب
اصلی کو قائم کر دیا.چنانچہ مَا وَذَعَكَ رَبُّكَ جواب ہے وَالَّيْلِ إِذَا سجی کا اور ما قلی جواب ہے
والضُّحیٰ کا.چونکہ غرض پوری ہو چکی تھی اور اب اس بات کی کوئی ضرورت تھی کہ واقعاتی
ترتیب کو بدلا جاتا اس لئے اللہ تعالی نے پہلی آیات کی ترتیب کو الٹ دیا اور فرمایا اے
محمد ا ا ا جب وَاليْلِ إِذا سجی میں بیان کردہ واقعہ ہوگا اور مکہ تجھے چھوڑنا پڑے گا تو اللہ تعالی
اس وقت تجھے چھوڑے گا نہیں.یہی وجہ ہے کہ غار ثور میں جب حضرت ابو بکر گھبرائے اور
انہوں نے کہا یا رسول اللہ دشمن اتنا قریب پہنچ گیا ہے کہ اگر وہ ذرا اپنے سر کو جھکائے تو
ہمیں اس غار میں سے دیکھ سکتا ہے تو رسول اللہ صلیم نے فرمایا لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللهَ مَعَنَا
مت کر خدا ہمارے ساتھ ہے.دوسری چیز فتح مکہ ہے اس کے لئے ماقلی کا لفظ خدا تعالیٰ نے استعمال کیا ہے.مگہ والوں کا
یہ خیال تھا کہ جو شخص مکہ پر حملہ کرے گا خدا کا غضب اس پر نازل ہوگا.وہ ابر ہ کے حملہ کو دیکھ
781
Page 790
چکے تھے کہ کس طرح وہ اپنے لاؤ لشکر سمیت حملہ آور ہوا اور پھر کس طرح خدا تعالیٰ نے اسے اپنے
غضب کا نشانہ بنادیا.وہ سمجھتے تھے کہ مکہ پر حملہ کرنے والا چونکہ خدا تعالیٰ کی نارضامندی کا مورد بنتا
ہے اس لئے وہ تباہ ہوجاتا ہے.مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیرے معاملہ میں ایسا نہیں ہوگا بلکہ شیحی کا
وقت اس بات کی شہادت دے گا کہ تیرا خدا تجھ سے ناراض نہیں.اگر وہ ناراض ہوتا تو تجھ پر
عذاب کیوں نازل نہ کرتا.تجھ پر اس کا عذاب نازل نہ کرنا بلکہ تیری تائید اور نصرت کرنا اور تیرے
راستہ سے ہر قسم کی روکوں کو دور کرنا اور تجھے اپنے لشکر سمیت فتح و کامرانی کا جھنڈا اڑاتے ہوئے
مگہ میں داخل ہونے کا موقع دینا بتارہا ہے کہ الہی منشاء یہی تھا کہ تو آئے اور اس بلد الحرام کو
فتح کر کے اس میں داخل ہو جائے.پس وَالَّيْلِ إِذا سجی میں بیان شدہ واقعہ کے ظہور نے بتادیا
کہ خدا تعالیٰ نے محمد رسول اللہ مال تعلیم کو نہیں چھوڑا اور والضحی میں بیان شدہ واقعہ نے بتادیا کہ
محمد رسول اللہ العلیم کے کسی فعل سے خدا تعالیٰ ناراض نہیں.حملا مصطفی روشنی اور سیجی اندھیرے پر دلالت کرتا ہے اور یہ دونوں حالتیں انسان پر آتی رہتی
ہیں.یعنی کبھی اس پر تکالیف آتی ہیں اور کبھی اس کے لئے خوشی کے سامان پیدا کئے جاتے ہیں.کبھی کامیابیاں اور ترقیاں حاصل ہوتی ہیں اور کبھی ناکامیاں اور تکالیف پیش آتی ہیں.یہ اتار
چڑھاؤ دنیا میں ہمیشہ ہوتا رہتا ہے.کبھی ترقی کا وقت آتا ہے تو کبھی تنزل کا، کبھی خوشی پہنچ جاتی
ہے تو کبھی غم کبھی اولاد پیدا ہوتی ہے کبھی مرجاتی ہے.کبھی بیمار ہو جاتا ہے کبھی تندرست ہو جاتا
ہے.کبھی دشمن کو مغلوب کر لیتا ہے اور کبھی دشمن کے عارضی طور پر جیتنے کا موقعہ آجاتا ہے.بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے یا ان پر کوئی مصیبت
آتی ہے تو جیسے قرآن مجید میں ہی کئی جگہ نقشہ کھینچا گیا ہے وہ شور مچانے لگ جاتے ہیں کہ بائے
مارے گئے ، ہائے مارے گئے.اس کے مقابل میں کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کو
ترقیات ملتی ہیں تو وہ تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں إِنَّمَا أَوْ تِيْتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي
(القصص (8) ہمیں جو کچھ ملا ہے اپنے زور بازو سے ملا ہے، ہمارے اندر قابلیتیں ہی ایسی تھیں
کہ ہمیں یہ ترقیات حاصل ہوتیں، ہم نے یوں کیا ہم نے ووں کیا اور پھر ہمیں یہ اعزاز حاصل
782
Page 791
ہوا.گویا جب ان
کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکات حاصل ہوتی ہیں یا ترقیات سے ان کو حصہ ملتا
ہے ان میں تکبر پیدا ہو جاتا ہے اور جب مشکلات آتی ہیں تو اس وقت بالکل مایوس ہو جاتے
ہیں.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جہاں دشمن ایسا ہے کہ اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ کہتا ہے
رَبِّي أَهَانِ (الفجر (17) میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا اور خوشی پہنچتی ہے تو کہتا ہے
رَبِّي أَكْرَمَنِ (الفجر (18) ہاں جی ہم تو ہیں ہی ایسے کہ خدا ہماری عزت کرتا.ایسے لوگوں کے
بالمقابل اے محمد رسول
اللہ تیری یہ حالت نہیں بلکہ والضُّحَى وَالَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَذَعَكَ رَبُّكَ
وما قلی.ہم تیری یہ دونوں حالتیں دشمنوں کے سامنے پیش کرتے ہیں.تیر انفس کامل اتنا اعلی
درجے کا ہے کہ تیر اسلوک اپنے رب سے ہمیشہ اس قسم کا ہوگا کہ ہر مایوسی اور تکلیف کے وقت
خدا تجھے بھولے گا نہیں بلکہ یادر ہے گا.مایوسی کبھی تیرے قریب بھی نہیں آئے گی اور خوشی
کے وقت کبھی تکبر تیرے پاس بھی نہیں پھٹکے گا.جب تجھ پر انعامات نازل ہوں گے تو یہ نہیں
کہے گا کہ میں نے یہ انعام بزور بازو حاصل کیا ہے اور اس طرح خدا تعالیٰ کو ناراض کر لے گا
بلکہ تو کہے گا کہ خدا تعالیٰ نے یہ انعام بخشا ہے اور اس طرح خدا تعالی کی خفگی کو پاس بھی نہیں آنے
دے گا.اسی طرح جب تجھے تکلیفیں آئیں گی اس وقت بھی تو خدا پر کوئی الزام نہیں لائے گا.بلکہ اسی
کے کنا ر عاطفت کی طرف تو ہر وقت جھکا رہے گا اور اس وجہ سے خدا تعالیٰ تیرے پاس آکھڑا ہوگا.پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالضُّحَى.وَالَّيْلِ إِذَا سَجَى.مَا وَذَعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى اے
محمد رسول
اللہ ! ہر رات جو تیری زندگی میں آئے گی، ہر رات جو تجھ پر گزرے گی وہ اس بات کو
ثابت کرنے والی ہوگی کہ مَا وَذَعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلی.کہ نہ تو تیرے خدا نے تجھے چھوڑا ہے اور
نہ تجھ سے ناراض ہوا ہے بلکہ وہ تجھ سے ہر گھڑی زیادہ قریب ہوتا جائے گا.کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہوتے ہیں جن پر دن چڑھتے ہیں تو وہ اپنے دنوں کوکھیل میں،
تماشا میں، جوئے میں ، شراب میں اور اسی قسم کی اور لغویات میں ختم کر دیتے ہیں اور جب رات
آتی ہے تو اس کو ناچ گانے اور سونے میں ختم کر دیتے ہیں.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مگر
اسم محمد علیم ایسے لوگوں کے مقابل پر تیر دن بھی اس قسم کا ہوگا اور تیری راتیں بھی اس قسم کی
783
Page 792
اور اسے کہہ
ہوں گی کہ ہر دیکھنے والے کے سامنے تیرے ساتھی ان دنوں اور ان راتوں کو پیش کر سکیں گے
ہ سکیں گے کہ بتاؤ کیا تمہارے دن محمد علی کے دنوں کی طرح ہیں اور کیا اس
حالت میں دن گزارنے والے کو کبھی خدا تعالیٰ چھوڑ سکتا ہے یا اس سے ناراض ہوسکتا ہے؟
اسی طرح تیری راتیں ایسی گزریں گی کہ تم ہر شخص کے سامنے اپنی ان راتوں کو پیش کر کے کہہ
سکو گے کہ میری راتوں کو دیکھو اور بتاؤ کہ کیا ایسی راتوں والے کو خدا تعالیٰ چھوڑ سکتا ہے؟
غرض فرمایا.وَالضُّحَى وَالَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَذَعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلی اے محمد عالم ہم تیرے
دنوں کو ایسا کر دیں گے اور تیری راتوں کو بھی ایسا کر دیں گے کہ تیرا دن بھی اس بات کی
شہادت دے گا کہ تجھے خدا نے نہیں چھوڑا.اور تیری رات بھی اس بات کی شہادت دے گی کہ
تیرا خدا تجھ سے ناراض نہیں ہے.یہ وہی دعوی ہے جو فَقَدْ لَبِثْتُ فِيْكُمْ عُمُرًا مِّنْ قَبْلِهِ
أَفَلَا تَعْقِلُونَ (یونس 17) میں کیا گیا ہے کہ میں تم میں ایک لمبی عمر گزار چکا ہوں کیا تم ثابت
کر سکتے ہو کہ میں نے اس عرصہ میں کسی ایک بدی کا بھی ارتکاب کیا ہو.اگر تم سب کے سب
مل جاؤ تب بھی میری چالیس سالہ ابتدائی زندگی پر کوئی داغ ثابت نہیں کر سکتے.مگر یہ دعوی تو
گزری ہوئی عمر کے متعلق ہے اور وَالضُّحى.وَالَّيْلِ إِذَا سَفِي مَا وَذَعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى
میں آئندہ زندگی کے متعلق دعوی کر دیا اور فرمایا کہ میرے دن تمہارے سامنے ہیں ایک کے
بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا اور تیسرے کے بعد چوتھا اور چوتھے کے بعد پانچواں دن
تمہارے سامنے گزرے گا.اسی طرح میری راتیں بھی تمہارے سامنے ہوں گی اور ایک کے
بعد دوسری رات گزرتی چلی جائے گی لیکن یا درکھو میری زندگی کا ہر دن جو گزرے گا وہ ثبوت ہوگا
اس بات کا کہ مَا وَذَعَنِى رَبِّي وَمَا قَلاني.اسی طرح ہر رات جو مجھ پر گزرے گی وہ ثبوت ہوگی
اس بات کا کہ مَا وَذَعَنِى رَبِّي وَمَا قَلانِي
غرض خدا تعالیٰ اس آیت میں محمد رسول اللہ علیم کو آپ کی صداقت کی ایک نئی دلیل
سکھاتا ہے اور فرماتا ہے میں یہ پیشگوئی کرتا ہوں کہ تیرا ہر دن میری رضامندی میں گزرے گا
اور تیری ہر رات میری رضا مندی میں گزرے گی.784
Page 793
وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الأولى.مد اور ( دیکھ توسہی کہ ) تیری ہر پیچھے آنے والی گھڑی پہلی سے بہتر ہوتی ہے.بہت سے
ترقی کرنے والے یکدم بڑھتے ہیں مگر آخر ٹھو کر کھاتے اور گر جاتے ہیں....پھر بہت سے
لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بڑے ذہین ہوتے ہیں مگر آخر میں پاگل ہو جاتے ہیں یا اپنی ذہانت کو
کھو بیٹھتے ہیں....عالم ہوتے ہیں مگر آخر میں جاہل ہو جاتے ہیں ، ان کا حافظہ خراب ہو جاتا ہے
اور وہ علم جو انہوں نے سیکھا ہوتا ہے سب بھول جاتا ہے.بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں جو محبوب
ہوتے ہیں مگر آخر وہ متروک ہو جاتے ہیں بلکہ جس قدر جسمانی محبوب ہوتے ہیں ان سب کا یہی
حشر ہوتا ہے.جوانی میں ہر شخص ان کی طرف دیکھتا ہے مگر جب ان کے دانت گر جاتے ہیں،
جب ان کی کمر جھک جاتی ہے، جب ان کے چہرہ پر جھریاں پڑ جاتی ہیں.تو بدصورت سے بد
صورت انسان بھی ان کو دیکھ کر ہنستا ہے اور کہتا ہے یہ کیسا بد شکل انسان ہے....تو کئی محبوب
ہوتے ہیں مگر آخر میں مبغوض ہو جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ہمارے رسول ! تیرا یہ
حال نہیں ہوگا.تجھ کو جوترقیات ملیں گی وہ ہر قدم پر بڑھتی چلی جائیں گی.پہلے مدینہ کا گردونواح
صاف ہوا، پھر مکہ فتح ہوا، پھر سارا عرب پھر شام اور عراق اور مصر فتح ہوئے.غرض ہر قدم آگے
ہی آگے بڑھتا چلا گیا.حمہ اللہ تعالیٰ نے مَا وَذَعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلی میں یہ مضمون بیان کیا تھا کہ محمد رسول اللہ
لام کی بسط کی حالت بھی خدا تعالیٰ کی معیت کا ثبوت ہو گی اور ان کی قبض کی حالت بھی
مَا وَذَعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلی کا ثبوت ہو گی.اب اس آیت میں یہ بتاتا ہے کہ ہم ایک بات کی
تمہیں تسلی دلا دیتے ہیں اور وہ یہ کہ تم ان روحانی لہروں میں یکساں نہیں چلو گے بلکہ ہمیشہ پہلے
سے اونچے نکلتے چلے جاؤ گے.ا خلال کے ایک معنے محبت شدیدہ کے بھی ہوتے ہیں
مفردات والے لکھتے ہیں یہ جو قرآن کریم میں آتا ہے کہ حضرت یعقوب کی نسبت ان کے
785
Page 794
بیٹوں نے کہا إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (یوسف 9) ہمارا باپ کھلی کھلی ضلال میں مبتلا ہے.اس میں ضلال کے معنے گمراہی کے نہیں بلکہ اشارة الى شَغَفِهِ بِيُوْسُفَ وَشَوْقِهِ إِلَيْهِ.اس میں
ان کی اس محبت اور شوق ملاقات کی طرف اشارہ ہے جو وہ حضرت یوسف کے متعلق اپنے دل میں
رکھتے تھے.گویا ضلال کے ایک معنے کمال درجہ کی محبت اور انتہا درجہ کے شوق کے بھی ہیں اسی
طرح قرآن کریم میں جو آتا ہے قَد شَغَفَهَا حُنَّا إِنَّا لَنَرُهَا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (يوسف (31) اس
میں بھی ضلال کے معنے بے انتہا محبت کے ہیں.غرض ضلال کا لفظ جہاں اور معنوں کے لئے
استعمال ہوتا ہے وہاں اس کے ایک معنے انتہا درجہ کی محبت کے بھی ہوتے ہیں.پہلے معنے تو اس آیت کے یہ ہیں کہ تمہیں ہمارا راستہ معلوم نہ تھا ہم شریعت سے بے خبر تھے،
تمہیں معلوم نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے کیا ذرائع ہیں.ایسی حالت میں ہم نے اپنی
شریعت تم پر نازل کی اور تمہیں اپنی طرف آنے کا راستہ دکھا دیا.آپ
کا پہلے اس کو چہ سے ناواقف ہونا ہر گز قابل اعتراض امر
نہیں.ہر صاحب شریعت نبی
پر جب خدا تعالیٰ کی وحی نازل ہوتی ہے تب اسے شرعی راستہ کا علم ہوتا ہے اس سے پہلے وہ اس
راستہ سے واقف نہیں ہوتا.یہی بات اس جگہ بیان کی گئی ہے کہ اسے محمد رسول اللہ علیم تھے
ہمارے راستے کا علم نہیں تھا پھر ہم نے اپنے فضل سے تجھے وہ راستہ دکھا دیا جس کی جستجو تیرے
دل میں پائی جاتی تھی.ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان احسانات کا ذکر فرمایا ہے جو اس نے رسول کریم علی
پر کئے.الخ يجدك يتيما فاوی میں
تو یہ بتایا کہ ہم نے تیرے جسمانی یتم میں تجھے جسمانی
رشتہ دار عطا کئے.تو اس بات کا محتاج تھا کہ کوئی شخص تیری پرورش کرنے والا ہوتا، مجھے محبت
اور پیار سے رکھتا اور تیری ضروریات کو پورا کرتا.سو اللہ تعالیٰ نے یکے بعد دیگرے ایسے لوگ
کھڑے کر دئیے جو انتہائی توجہ کے ساتھ تیری پرورش کا فرض سر انجام دیتے رہے اور ہر موقع
پر جسمانی طور پر تیری مدد کرتے رہے دوسری طرف روحانی یتیم کے لئے ہم نے اپنی محبت اور
786
Page 795
اپنا فیضان تجھ کو عطا کیا اور تجھے ایسی تعلیم عطا کی جو مکہ والوں کو قعر مذلت سے اٹھا کر ترقی کے
بلند تر مینار پر پہنچانے والی ہے.اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ ایک دعوی تھا جو محمد رسول اللہ
عالی کی طرف سے کیا جا رہا تھا مگر دعوی وہ تھا جسے پر کھا جاسکتا تھا.قرآن کریم لوگوں کے
سامنے موجود تھا اور انہیں کہا جا سکتا تھا کہ آؤ اور دیکھو کہ اس میں قوموں کو ابھارنے والی تعلیم
موجود ہے یا نہیں اسی طرح رسول کریم علیم کے قرب اور آپ کے تعلق باللہ کو وہ آپ کی
دعاؤں اور آپ کے نشانات کے ذریعہ دیکھ سکتے تھے.غرض نہ وہ آلَمْ يَجِدُكَ يَتِيما فَأُویٰ کی
صداقت کا انکار کر سکتے تھے اور نہ وَجَدَكَ ضَالًا فَهَدی کی صداقت کا انکار کر سکتے تھے.اللہ تعالیٰ ان دو مثالوں کو پیش کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ جب کہ تیری جسمانی پرورش بھی ہم
نے کی اور تیری روحانی پرورش بھی ہم نے کی اور ہر قدم پر تیرے ساتھ اپنی تائید رکھی.تو جسمانی
توجہ کا محتاج تھا تو ہم نے تیری جسمانی پرورش کی طرف توجہ کی.تو روحانی توجہ کا محتاج تھا تو
ہم نے تیری روح پر شفقت کی نظر ڈالی.جب ہماری محبت تیرے دل میں پیدا ہوئی تو ہم نے
تجھے اپنا چہرہ دکھا دیا اور جب بنی نوع انسان کی محبت تیرے دل میں پیدا ہوئی اور ان کی خرابیوں
نے تجھے بے چین کر دیا تو ان کی اصلاح اور حالات کی درستی کے لئے اپنی شریعت تجھ پر نازل
کر دی.جب ہم اپنی محبت اور اپنے سلوک کا اس قدر نمونہ تیری ذات میں دکھا چکے ہیں تو یہ
ثبوت ہے اس بات کا کہ آئندہ ترقیات اور ضحی کے متعلق جو خبر دی گئی ہے وہ بھی پوری ہو
کر رہے گی.جس خدا نے تجھے پیچھے نہیں چھوڑ اوہ آئندہ تجھے کس طرح چھوڑ سکتا ہے؟
وَوَجَدَكَ عَائِلاً فَأَغْلی کے دو معنے ہیں.اوّل یہ کہ ہم نے تجھ کو کثیر العیال پایا.اور
تیری ضرورت پوری کر دی.دوسرے یہ کہ ہم نے دیکھا کہ تو ہی ایک ایسا شخص ہے جو ہر یتیم
اور بے کس کی خبر گیری کرتا ہے اس لئے ہم نے بھی تجھے دولت دے دی تا کہ تو ان کی.ضروریات کو پورا کر سکے.پہلے معنوں کے لحاظ سے اس آیت کا یہ مفہوم ہو گا کہ تو اپنے عیال کی
خبر گیری کے قابل نہ تھا مگر ہم نے دولت دے کر تیری غربت کو دور کر دیا.اور دوسرے معنوں
787
Page 796
کے لحاظ سے اس آیت کا یہ مفہوم ہے کہ تیرے اندر یہ جذ بہ شوق پایا جاتا تھا کہ تو ہر مسکین اور
یتیم کو پناہ دے.جو بھی درماندہ اور بے کس انسان تجھے نظر آتا تو اسے اپنی آغوش شفقت
میں لے لیتا.اس کے سر پر اپنی محبت کا ہاتھ رکھتا اور اس کی ضروریات کو پورا کرنے کی
کوشش کرتا.جب ہم نے تیرے اس جذبہ محبت اور جذبہ ہمدردی کو دیکھا تو ہم نے بھی اپنی
دولت تیرے سپرد کر دی تا کہ تو ہمارے بے کس اور نادار بندوں کا کفیل ہو.یہاں دولت سے
مراد صرف جسمانی دولت نہیں بلکہ روحانی دولت بھی مراد ہے اور یتامیٰ ومساکین سے مراد بھی
صرف جسمانی بیتامی و مساکین نہیں بلکہ روحانی بیتامی و مساکین بھی مراد ہیں.غرض اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہ صرف تجھے ہم نے پالا اور تیری پرورش کا
سامان کیا بلکہ تیرے ذریعہ سے اور ہزاروں یتامیٰ و مساکین کی پرورش کا بھی ہم نے انتظام کر
دیا.جسمانی یتیم، جسمانی مسکین ، جسمانی غریب اور جسمانی نادار روٹی کھا کر شہادت دے رہے
رض
ہیں.کہ محمد رسول اللہ علیم ایک راستباز انسان ہیں اور روحانی یتیم ابوبکر اور عمر اور عثمان اور
علی اور طلحہ اور زبیر تیری تعلیم سے مطمئن ہو کر گواہی دے رہے ہیں کہ ہم بڑے بھوکے تھے
اگر سیری حاصل ہوئی تو اسی خوان بدی سے جو اس پاک نفس نے پیش کیا.یہ ثبوت ہے اس
بات کا کہ آئندہ بھی خدا ہمیشہ تیرے ساتھ ہو گا.ہمیشہ تیری تائید کرے گا.ہمیشہ تجھے اپنی نصرت
عطا کرے گا.جو خدا آج تک تیرے کام آتا رہا ہے جس نے ایک لمحہ کے لئے بھی تجھے کبھی
نہیں چھوڑا.وہ آئندہ تجھے کس طرح چھوڑ سکتا ہے؟
اس آیت کے یہ بھی معنے ہیں کہ آپ کے روحانی عیال جوں جوں زیادہ ہوتے جائیں
گے اللہ تعالیٰ ان کی خبر گیری کے سامان پیدا کرتا جائے گا.چنانچہ جس قدر معلم علم دین
رسول کریم صل ملک کو ملے اور کسی نبی یا بزرگ کو نہیں ملے.اسی وجہ سے آپ نے فرمایا
أَصْحَابِي كَالنُّجُوْمِ بِأَتِهِمِ اقْتَدَيْتُمُ اهْتَدَيْتُمْ - میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں جس کے
پیچھے بھی چلو گے ہدایت پا جاؤ گے.788
Page 797
فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرُ میں اسی طرف اشارہ ہے کہ اے محمد رسول اللہ علم تو یتیم تھا ہم
نے تجھے پالا.اب دنیا میں ہمارے اور بھی بہت سے یتیم بندے ہیں ان کی پرورش تیرے ذمہ
ہے اور تیرا فرض ہے کہ تو ان کی نگرانی رکھے اور ان کی تکالیف کا ازالہ کرے.لا تقهر کہہ کر اس امر کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ یتیم کی پرورش اس رنگ میں
نہیں کرنی چاہئے کہ وہ خراب ہو جائے.یعنی نہ ایسی سختی کرو کہ جس کے نتیجہ میں اس کے قویٰ
دب جائیں اور وہ ترقی سے محروم ہو جائے اور نہ ایسی نرمی کرو کہ جس سے ناجائز فائدہ اٹھا کر وہ
اپنے اوقات اور اپنے قومی کو برباد کر دے.قھر کے معنے دراصل غلبہ کے ہوتے ہیں.پس لا
تقهر کے معنے یہ ہوئے کہ اس سے ایسا معاملہ نہ کرو جس کے نتیجہ میں تم اس کے قوائے دماغیہ
اور جسمانیہ پر غالب آجاؤ اور اس کی ترقی کو نقصان پہنچادو.انسانی ترقی کو دو ہی طرح نقصان
پہنچتا ہے یا بے جا سختی سے یا بے جانرمی اور محبت سے.پس لا تقهر کہہ کر اللہ تعالیٰ نے بے جا
سختی سے بھی روک دیا اور بے جا نرمی سے بھی منع فرما دیا.اور نصیحت کی کہ یتیم سے تم ایسا ہی
معاملہ کرو جو اس کی اچھی تربیت کے لئے ضروری ہو.فرماتا ہے سائل کو تم جھڑ کو نہیں کیونکہ تم بھی سائل تھے.محبت کی بھیک ہم سے مانگنے کے
لئے آئے تھے.ہم نے تمہارے سوال کورڈ نہ کیا بلکہ تمہارے دامن کو گوہر مقصود سے بھر کر
لوٹایا.اب تم سے اور لوگ محبت کی بھیک مانگنے آئیں گے.تمہارا فرض ہے کہ تم ان سائلوں کی
طرف ہمہ تن متوجہ رہو اور ان کی خواہشات کو پورا کرو.أمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَيْت
تحدیث نعمت دو طرح ہوتی ہے.ایک اس طرح کہ انسان علیحدگی میں اللہ تعالی کے
احسانات کا شکر ادا کرے اور اس کے پیہم فضلوں کو دیکھ کر سجدات شکر بجالائے اور زبان کو اس
کی حمد سے تر رکھے.دوسرا طریق تحدیث نعمت کا یہ ہوتا ہے کہ لوگوں میں اللہ تعالیٰ کے
احسانات کا ذکر کیا جائے اور انہیں بتایا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا فضل کیا.فرماتا ہے ہم
نے
جو نعمتیں تجھے عطا کی ہیں ان کا خود بھی شکر ادا کرو اور اپنے رب کی ان نعمتوں کا لوگوں میں بھی
789
Page 798
خوب چرچا کرو.یا خدا تعالیٰ نے جو نعمتیں تجھے دی ہیں ان سے خود بھی فائدہ اٹھاؤ اور اپنے جسم پر
ان کے آثار کو ظاہر کرو.اور کچھ حصہ صدقہ وخیرات کے طور پر لوگوں میں بھی تقسیم کرو.اس سورۃ کے آخر میں جو تین باتیں بیان کی گئیں ہیں.یہ پہلی بیان کردہ تین باتوں کے
مقابل میں ہیں.پہلے فرمایا تھا.(1) أَلَمْ يَجِدُكَ يَتِيمَا فَأَوَى.(2) وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَى.(3) وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَاغْلی تم یتیم تھے ہم نے تمہیں پناہ دی.تم ہماری محبت اور اپنی قوم کی
نجات کے طالب تھے ہم نے تمہیں اپنی محبت بھی عطا کر دی اور قوم کی نجات کا سامان بھی عطا کر
دیا.اسی طرح تم روحانی اور جسمانی بیتامی سے گھرے ہوئے تھے ہم نے دونوں کی ضروریات کو
پورا کرنے کا سامان بھی تجھے دے دیا.اب تیرا بھی فرض ہے کہ تو یتامی سے ایسا سلوک نہ کر جو
اُن کی طاقتوں کو توڑنے والا ہو.تو ہماری محبت کے سائلوں کو جو تیرے دروازہ پر آئیں کبھی
مایوس مت لوٹا بلکہ جس طرح ہم نے تیری مراد میں پوری کی ہیں تو ان کی مرادوں کو پورا کر.اور
پھر یہ بھی دیکھ کہ ہم نے تجھے عائل بنایا تھا پھر مجھے غنی کر دیا.اب تمہارا کام یہ ہونا چاہئے کہ ہم
نے تجھ پر جو احسانات کئے ہیں ان کا تو شکر ادا کر.ہماری نعمتوں سے خود بھی فائدہ اٹھا اور لوگوں
میں بھی ان نعماء کوتقسیم کر.یہ اسلامی تعلیم نہیں ہے کہ انسان کو اگر کوئی نعمت ملے تو وہ اسے رد کر
دے اور اس سے فائدہ نہ اٹھائے.بدقسمتی سے مسلمانوں کے ایک طبقہ میں روحانیت کا مفہوم
نہ سمجھنے کے نتیجہ میں یہ خیال پیدا ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعماء کا استعمال روحانیت کے خلاف
ہے.اچھا کھانا کھانا یا اچھا کپڑا پہنا یا اعلیٰ درجہ کی اشیاء سے فائدہ اٹھانا روحانی لوگوں کا کام
نہیں ہو سکتا.مگر یہ لوگوں کی خود ساختہ روحانیت ہے اسلام اور عرفان سے اس کا کوئی تعلق
نہیں.الہی حکم یہی ہے کہ أَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَيّت.انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی
نعمت ملے وہ اس سے خود بھی فائدہ اٹھائے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائے.کاہنوں کی طرح
ان نعمتوں کو رد نہ کر دے.اس آیت کے روحانی لحاظ سے یہ معنے ہوں گے کہ ہم نے جو تعلیم تجھے عطا کی ہے اس پر خود
بھی عمل کرو اور دوسروں سے بھی عمل کراؤ.اور جسمانی لحاظ سے اس آیت کے یہ معنے ہیں کہ ہم
790
Page 799
نے جو نعمتیں تجھے دی ہیں ان سے خود بھی فائدہ اٹھاؤ اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاؤ.(ماخوذ از تفسیر کبیر از حضرت خلیفہ امسیح الثانی رضی اللہ عنہ.زیر تفسیر سورۃ الضحی)
حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز فرماتے ہیں:
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَيّت (الضحی (12) اور جہاں تک تیرے
رب کی نعمت کا تعلق ہے تو اسے بکثرت بیان کیا کر.1905ء میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی الہاما یہ فرمایا تھا کہ
وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَیّت.پس یہ احمدی کا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو بے شمار نعمتیں نازل ہو
رہی ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا چلا جائے اور جیسا کہ شکر گزاری کے جذبات کے ساتھ نیک اعمال
بھی ہونے چاہئیں ، عبادتوں کے علاوہ حقوق العباد کی ادائیگی کی بھی کوشش ہونی چاہیئے.یہ
بھی ہر احمدی کا فرض ہے کہ ایسا کرے....جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ ستمبر 1905ء میں
حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ الہام ہوا تھا کہ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَيثُ اس لحاظ
سے اس سال کے اس آخری جمعہ کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے تشکر سے پُر جذبات
کے ساتھ دعاؤں کا دن بنا لیں.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں کہ جمعہ کے دن کے
دوران در و د خاص اہمیت رکھتا ہے اور پھر یہ شکر اور یہ درود ہمیشہ آپ سب کی زندگیوں کا حصہ
بن جائے اور پھر اس شکر کے مضمون کے ساتھ نئے سال کا آغاز ہو.اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا
شکر ادا کریں جو گزشتہ سال عطا ہوئی تھیں تا کہ جو آئندہ آنے والا سال ہے وہ پہلے سے بڑھ کر
برکات لانے والا ہو.احمدیت کی فتح کے جو آثار ہم دیکھ رہے ہیں وہ مزید قریب تر آجائیں.پس خالصہ اللہ تعالیٰ کے لئے کی گئی ، شکر گزاری کے جذبات سے پر ہماری عبادتیں ہی ہیں جو
اللہ تعالیٰ کے فضلوں اور جماعت کی آئندہ ترقیات کو ہمارے قریب تر لے آئیں گی.پس آگے
بڑھیں اور اللہ تعالیٰ کے فضلوں سے جھولیاں بھرنے کے لئے اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے
بنتے چلے جائیں.حقوق اللہ کی ادائیگی بھی کریں اور حقوق العباد کی ادائیگی بھی کریں.اللہ تعالیٰ
791
Page 800
سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے.( خطبه جمعه فرمودہ حضرت خلیفة المسیح الخامس اید والله، فرموده 30 / دسمبر 2005ء - خطبات مسرور جلد سوم صفحہ 756 -758)
792
Page 801
********
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ )
وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ
الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ
وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَة
فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًان
إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًان
فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْةٌ
وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبُ &
سورة الم نشرح
1 - ( میں ) اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا
( اور ) بار بار رحم کرنے والا ہے ( پڑھتا ہوں)
2.کیا ہم نے تیرے لئے تیرے سینہ کو کھول نہیں دیا.3.اور تیرے اس بوجھ کو تجھ پر سے اتار کر
پھینک نہیں دیا.4.ایسا بوجھ جس نے تیری کمر توڑ رکھی تھی.5.اور تیرے ذکر کو بھی ہم نے بلند کر دیا ہے.6.پس ( یاد رکھ کہ ) اس تنگی کے ساتھ ایک
بڑی کامیابی مقدر ہے.7- (ہاں) یقیناً اس تنگی کے ساتھ ایک (اور بھی)
بڑی کامیابی ( مقدر) ہے.8.پس جب ( بھی ) تو فارغ ہو تو ( خدا تعالیٰ سے
ملنے کے لئے ) پھر کوشش میں لگ جا..اور تو اپنے رب کی طرف متوجہ ہو.793
Page 802
حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں:
إِنَّ فِي ذلِكَ لَبُهْرَى لِكُلِّ مَنْ تَزَكَّى، وَإِشَارَةٌ إِلى أَنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوُا فِي زَمَانٍ ضَرًّا
وَضَيْرًا، فَيَرَوْنَ فِي آخَرَ نَفْعًا وَ خَيْرًا ، وَيَرَوْنَ رُخَا بَعْدَ بَلَا فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا
سر الخلافة ، روحانی خزائن جلد 8 صفحه 361)
اس میں ہر تزکیہ اختیار کرنے والے کے لئے بشارت ہے اور اس بات کی طرف اشارہ ہے
کہ جب لوگ ایک زمانہ میں دکھ اور تکلیف دیکھیں گے تو بعد میں وہ نفع اور بھلائی بھی دیکھیں گے
اور دین و دنیا میں ابتلادیکھنے کے بعد خوشحالی کا زمانہ بھی دیکھیں گے.( ترجمہ از مرتب)
یہ قاعدہ کی بات ہے کہ جس قدر انسان اعلیٰ مراتب اور مدارج کو حاصل کرنا چاہتا ہے
اسی قدر اس کو زیادہ محنت اور وقت کی ضرورت ہوتی ہے.پس استقلال اور ہمت ایک ایسی
عمدہ چیز ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو انسان کامیابی کی منزلوں کو طے نہیں کر سکتا.اس لئے ضروری ہوتا
ہے کہ وہ پہلے مشکلات میں ڈالا جاوے.اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا اسی لئے فرمایا ہے.احکم جلد 6 نمبر 45 مورخہ 17 دسمبر 1902 ، صفحہ 2)
ساری لذت اور راحت دکھ کے بعد آتی ہے.اسی لئے قرآن شریف میں یہ قاعدہ بتایا
ہے اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا.اگر کسی راحت سے پہلے تکلیف نہیں تو وہ راحت راحت ہی نہیں
رہتی.اسی طرح پر جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو عبادت میں لذت نہیں آتی ان کو پہلے اپنی جگہ سوچ
لینا ضروری ہے کہ وہ عبادت کے لئے کس قدر دکھ اور تکالیف اُٹھاتے ہیں.جس جس قدر دکھ
اور تکالیف انسان اُٹھائے گا وہی تبدیل صورت کے بعد لذت ہو جاتا ہے.میری مرادان
دکھوں سے نہیں کہ انسان اپنے آپ کو بیجا مشقتوں میں ڈالے اور مالا يُطاق تکالیف اُٹھانے کا
دعوی کرے؟ ہر گز نہیں.الحکم جلد 7 نمبر 9مورخہ 10 مارچ 1903ءصفحہ 1)
انسان کی زندگی کے ساتھ مکروہات کا سلسلہ بھی لگا ہوا ہے.اگر انسان چاہے کہ میری
794
Page 803
ساری عمر خوشی میں گزرے تو یہ ہو نہیں سکتا.فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا -
زندگی کا چکر ہے.جب تنگی آوے تو سمجھنا چاہیے کہ اس کے بعد فراخی بھی ضرور آئے گی.( بدر جلد 1 نمبر 31 مورخہ 31اکتوبر 1905ء صفحہ 1)
حضرت خلیفہ المسیح الاول رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:
اس سے ماقبل کی سورۃ سورۃ الضحی میں ظاہری وجسمانی انعامات کا ذکر تھا.اور اس
سورہ شریفہ میں آپ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو روحانی نعمتیں ہوئیں ان کا ذکر ہے.شرح صدر ایک کشفی کیفیت تھی جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر وارد ہوئی تھی.جبکہ آپ کی عمر
دس سال سے کچھ اوپر تھی اور بعد میں نبوت کے زمانہ میں بھی دوبارہ وہ کشفی اور روحانی معاملہ
شرح صدر کا آپ سے کیا گیا.ظاہری اثر اس کا آپ پر یہ تھا کہ جو وسیع الحوصلگی آپ
کی تھی اس
کی نظیر اوروں میں کیا اولوالعزم نبیوں میں بھی پائی نہیں جاتی.نوح علیہ السلام نے قوم سے دکھ
اُٹھا کر رب لا تَذَرُ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَفِرِينَ دَيَّارًا (نوح 27) کہہ دیا اور موسیٰ علیہ الصلوۃ
والسلام قوم سے دکھ اُٹھا کر وَاشْدُدْ عَلى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ لأَلِيْمَ
(یونس (89) کی دعا کرتے ہیں.مگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طائف کے شریروں سے
اس قدر پتھروں کی مار سے دکھ اٹھایا کہ سارا بدن آپ کا خون آلود ہو گیا.اس وقت آپ نے
فرمایا تو یہ فرمایا.کہ اللّهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُون (بخاری کتاب الانبیاء باب 54)
جبرئیل علیہ السلام نے طائف والوں کی ہلاکت کے لئے عرض کیا تو فرمایا کہ نہیں میں امید رکھتا
ہوں کہ ان کی نسل سے مسلمان پیدا ہوں گے.پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نو (9) بیبیاں تھیں.انسان ایک دو بیبیوں کی ناز برداری سے تنگ آ جاتا ہے.مگر آپ سے تمام بیبیاں خوش تھیں.آیت تطہیر کے اترنے پر جو سورۃ الاحزاب میں ہے.آپ نے سب بیویوں کو اختیار دے دیا
تھا.مگر کسی نے بھی آپ کے حسن اخلاق اور انشراح صدر کو معلوم کر کے آپ سے جدائی کو پسند
نہ کیا.یہ کیسا انشراح صدر اور عالی حوصلہ تھا کہ فتح مکہ کے روز جن ظالموں نے آپ کو شہر سے
795
Page 804
نکالا تھا اور آپ کے اصحاب کو طرح طرح کی بے رحمیوں سے قتل کیا تھا.ان سب کو آپ
نے لا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ کہہ کر یک لخت معافی دے دی.فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ
ضمیمه اخبار بدر قادیان 15 دسمبر 1912ء)
یہ سنت انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی ہے کہ ظاہری کوشش اور محنت کے ساتھ باطنی
عقد ہمت دعا اور توجہ الی اللہ ان کا کام ہوتا ہے.حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے
ظاہری محنتوں سے کعبہ کو بنا یا مگر ساتھ ہی عقدِ ہمت سے دعائیں بھی کیں.رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (البقره 128)
محنت ہو، کوشش ہو، مگر دعا نہ ہو.کام نا تمام ہے.اسی طرح صرف دعا ہی ہومگر کچھ محنت نہ
ہو.پھر بھی کام نا تمام ہے.(ضمیمه اخبار بدر قادیان 15 اگست 1912ء
(ماخوذ از حقائق الفرقان)
حضرت خلیفۃالمسیح الثانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:
یہ سورۃ مکی ہے.پہلی سورۃ میں رسول کریم علیہ کے انجام کے اچھا ہونے کا ذکر تھا
جیسا کہ فرمایا تھا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرُ لكَ مِنَ الْأَوْلى.ما اب سورۃ الانشراح میں اس دعویٰ کے متعلق کہ رسول کریم ملایم کا انجام اچھا ہوگا مزید
روشنی ڈالی گئی ہے.اور پچھلی سورۃ کے تسلسل میں اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون بیان فرمایا ہے کہ
انجام کے اچھا ہونے کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں اگر وہ علامتیں کسی شخص میں موجود ہوں تو وقت
سے پہلے لوگ قیاس کر سکتے ہیں کہ خدا تعالی کی مدد اس شخص کو حاصل ہے یعنی انجام تو جب ہوگا
سو ہوگا.محمد رسول اللہ علیم کے اچھے انجام کو بعض علامتوں کے ساتھ پہچانا بھی جاسکتا ہے.چنانچہ چارا ہم علامتیں اللہ تعالیٰ اس جگہ بیان کرتا ہے.اول یہ کہ انسان کو خود اپنے دعووں پر شرح صدر ہو.796
Page 805
دوم جس مقصد کو لے کر وہ کھڑا ہو اس کو پورا کرنے کے ذرائع اس کو میسر آجائیں.اور تیسرے یہ کہ لوگوں کی توجہ اس کی طرف پھر جائے.چوتھے یہ کہ یہ سامان الہی تقدیر کے ماتحت پیدا ہوں.جب یہ چار چیزیں کسی شخص کو حاصل ہو جائیں تو ابتدا ہی سے یہ قیاس کیا جاسکتا ہے کہ وہ
شخص غالب آجائے گا.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محمد رسول اللہ صل العلیم یہ چاروں باتیں تجھے
حاصل ہیں اس صورت میں تیرے مخالفین کو سمجھ لینا چاہئے کہ تیرے انجام کی بہتری کے متعلق
کوئی شبہ نہیں کیا جا سکتا.ہر ملک اور ہر قوم میں یہ دستور پایا جاتا ہے کہ ان میں سے جب کسی شخص کو اطمینان
حاصل ہو جاتا ہے یا کسی حقیقت پر اس کا دل تسلی پا جاتا ہے تو ایسے موقع پر ہمیشہ اظہار اطمینان
کے لئے وہ شرح صدر کا لفظ استعمال کرتا ہے.اردو میں بھی کہتے ہیں کہ فلاں بات کے لئے میرا
سینہ کھل گیا.أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدرَك میں گو الفاظ استفہامی یعنی سوالیہ استعمال کئے گئے ہیں اور
اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ کیا ہم نے تیرے سینہ کو نہیں کھولا؟ مگر مفہوم یہ ہے کہ تو جانتا ہے
ہم نے تیرے سینہ کو کھول دیا ہے.الم نشرح لك صَدْرَكَ کے یہ معنے نہیں کہ تجھ سے ہم سوال کرتے ہیں کہ کیا تیرا سینہ
کھولا گیا ہے یا نہیں؟ بلکہ اس کے یہ معنے ہیں کہ تو بھی جانتا ہے کہ تیرا سینہ ہم نے کھول دیا
ہے اور تیرے دشمن بھی جانتے ہیں کہ تیرا سینہ ہم نے کھول دیا ہے.اس جگہ یہ سوال ہو سکتا ہے کہ کیوں نہ سیدھے سادے الفاظ میں یہ کہہ دیا ہے کہ ہم نے
تیرا سینہ کھول دیا ہے.اس کا جواب یہ ہے کہ اگر یہ کہا جاتا کہ ہم نے تیرا سینہ کھول دیا ہے تو
اس سے صرف ایک خبر کا مفہوم نکلتا ہے.یعنی اللہ تعالیٰ اطلاع دیتا ہے کہ ہم نے سینہ کو کھول
دیا.لیکن یہ مفہوم نہ نکلتا کہ اس شرح صدر کا کوئی ظاہر نتیجہ بھی نکلا ہے یا نہیں اور
رسول کریم علی امی کو بھی اس شرح صدر کا کوئی احساس ہوا ہے یا نہیں اور کفار نے بھی اس کا
797
Page 806
کوئی ثبوت دیکھا ہے یا نہیں اور یہ مضمون ظاہر ہے کہ بہت ہی نامکمل ہوتا لیکن آلخر نشرخ
لك صدرك کہہ کر اس امر پر زور دے دیا کہ ہم نے تیرا سینہ کھول دیا ہے اور یہ امر تو بھی جانتا
ہے اور تیرے دشمن بھی جانتے ہیں.یعنی ایک چھپی ہوئی بات نہیں ایک ظاہر اور کھلا نشان ہے
جس انکار کوئی نہیں کر سکتا.غرض ایسا فقرہ استعمال کر کے جس کے معنے یہ ہوتے ہیں کہ یہ
حقیقت دوسروں پر مخفی نہیں شرح صدر کی اہمیت کو ایسا واضح کر دیا ہے کہ اور کوئی مختصر الفاظ
اس مضمون کو بیان نہ کر سکتے تھے.الَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ اپنے اندر تصدیق مخاطب کا مضمون بھی رکھتا ہے اور اس کے
معنی یہ ہیں کہ مخاطب اس علم میں ہمارا شریک ہے.وہ اس واقعہ سے انکار نہیں کرسکتا.اللہ تعالیٰ
فرماتا ہے الخ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہم نے تیرا سینہ اس طرح
نہیں کھولا کہ تو خود بھی اس بات کی گواہی دے گا اور تجھے علم ہے کہ ہم نے تیرا سینہ کھول دیا ہے.شرح کے معنی (1) کھولنے (2) پھیلانے (3) سمجھانے (4) محفوظ کر دینے
(5) اچھی طرح بیان کرنے کے ہیں.سینہ کھولنے کے معنی مادہ قبولیت کے پیدا ہو جانے کے ہیں اور چونکہ یہ محاورہ اچھے معنوں
میں استعمال ہوتا ہے اس لئے اس کے معنی یہ ہوں گے کہ اچھی باتوں کی قبولیت کے لئے دل
آمادہ رہتا ہے یا کسی خاص معاملہ کے متعلق دل تسکین پالیتا ہے.اسے اس بات پر یقین کامل
ہو جاتا ہے تو اسے شرح صدر کہتے ہیں.جب یقین ایسے کمال کو پہنچ جائے کہ اس میں معجزانہ
رنگ پیدا ہو جائے تو اسے خدا تعالیٰ کی طرف سے شرح صدر کہتے ہیں.اور جب ایسے امور کے
متعلق یقین ہو جو غیبی ہوں اور جن پر یقین پیدا ہونا الہی تصرف کے نتیجہ میں ہو سکتا ہو تو اسے بھی
خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے.اور انکار ابطالی کا استعمال جو در حقیقت اثبات پر دلالت
کرتا ہے یہ بتاتا ہے کہ وہ امر پوشیدہ نہیں بلکہ اس کی حقیقت ظاہر و باہر ہوچکی ہے.ان معنوں کی رُو سے اس آیت کے یہ معنی ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ علیم کو
صداقتوں اور نیکیوں کو ماننے اور ان پر عمل کرنے کے لئے بہت بشاشت قلب عطا فرمائی
798
Page 807
تھی.اور وہ امور سماویہ جو امور غیبیہ پر مشتمل تھے ان پر بڑا ز بر دست یقین بخشا تھا.اور یہ دونوں
امر بار بار اس طرح ظاہر ہو چکے تھے کہ آپ کے مخالفوں کو بھی ان کے انکار کی جرأت نہیں ہو
سکتی تھی.اور اگر یہ تینوں باتیں کسی شخص میں پائی جائیں تو اول تو یہ اس کی سچائی کا ثبوت ہوتی
ہیں.دوسرے یہ اس بات کا ثبوت ہوتی ہیں کہ وہ شخص ضرور کوئی نیک تغیر دنیا میں پیدا کر کے
چھوڑے گا.دوسرے معنے سینہ کھلنے کے یقین کامل کے کئے گئے ہیں.رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم کو اپنی صداقت پر جو یقین تھا وہ مخفی امر نہیں.حضرت موسیٰ علیہ السلام تو دعا کرتے ہیں کہ رب اشرح لي صدارتی (طه 26) اے میرے
رب میرا سینہ کھول دے.جس کے معنے یہ ہیں کہ خدایا مجھے وہ یقین حاصل ہو جائے جس کے
بعد میں یہ سمجھوں کہ اگر یہ کام نہ ہوا تو میرا قصور ہے لیکن اس کے مقابلہ میں رسول کریم علیم کو
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے یہ چیز تجھے دے دی ہے اور نہ صرف تجھے دے دی ہے بلکہ تو بھی
جانتا ہے کہ ہم یہ چیز تجھے دے چکے ہیں.یعنی ایسے رنگ میں یہ چیز تجھے دی ہے کہ تجھ پر بھی
حقیقت پوری طرح منکشف ہو چکی ہے.رسول کریم ملی کی ساری زندگی اس آیت کی صداقت کا ثبوت بہم پہنچاتی ہے.شروع
سے لے کر آخر تک آپ کی زندگی سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا سینہ اسلام اور اس
کی تعلیم کے لئے کھول دیا تھا اور وہ آخر تک کھلا رہا.دوسرے معنے شرح کے محفوظ رکھنے کے ہوتے ہیں.ان معنوں کی رُو سے آیت کے
یہ معنے ہوں گے کہ کیا ہم نے تیرے سینہ کو تیرے لئے محفوظ نہیں کر دیا.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے تیرے فائدہ کے لئے (لک کالام فائدہ کے معنے دیتا ہے ) تیرا
سینہ کھول دیا ہے یعنی وہ روحانی امور جو تیرے لئے نفع بخش ہوتے ہیں ان کے قبول کرنے کے
لئے ہم نے تیرا سینہ محفوظ کر دیا ہے.یعنی اس کے خلاف بدی کی کوئی تحریک تیرے سینہ میں
داخل نہیں ہوسکتی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ تیرا سینہ نیکی کے لئے محفوظ رہنا چاہئے.799
Page 808
کامل راہنمائی دنیا کی ایسا ہی انسان کر سکتا ہے جس کا سینہ خدا تعالیٰ نے شیطان کے اثر سے
محفوظ کر دیا ہو.تیسرے معنے شرح کے سمجھانے کے ہیں.ان معنوں کی رُو سے اس آیت کے یہ معنے
ہوں گے کہ ہم نے تیرے دل میں حقائق اشیاء اتار دیے اور خود تیرا استاد بن کر تجھ کو سمجھایا.یعنی
محمد رسول اللہ یا تعلیم کو سمجھانے اور حقیقت بتانے والا خود اللہ تعالیٰ تھا.الم نشرح لك صدرك کے ایک اور معنے بھی ہیں جو رسول کریم علیم کی عظمت اور
آپ کی بلندی درجات کا ایک کھلا ثبوت ہیں اور وہ معنے یہ ہیں کہ دنیا میں دو قسم کے علوم ہوتے
ہیں.ایک علم خارجی ہوتا ہے اور ایک علم اندرونی ہوتا ہے.یکمیل علم کا انحصار انہیں دوملیکوں
پر ہوتا ہے.اور یہ علم النفس کا ایک بہت بڑا نکتہ ہے جس سے بہت سے لوگ ناواقف ہوتے
ہیں.وہ سمجھتے ہیں کہ علم خارجی ہی اصل علم ہے.حالانکہ علم خارجی بہت محدود علم ہوتا ہے اور وہ
مکمل نہیں ہوتا جب تک اس کے ساتھ علم اندرونی بھی شامل نہ ہو.پس فرماتا ہے الم نشرح لك صدرك اے محمد عالم کیا تو اس بات کا گواہ نہیں کہ ہم
نے تیرے اندر یہ مادہ پیدا کیا ہے کہ جب تجھ پر ایک آیت نازل ہوتی ہے تو اس کے تمام
مالہ اور مَا عَلَیہ تیرے سامنے آجاتے ہیں.جو حکم بھی نازل ہوتا ہے اس کی باریکیاں اور
وسعتیں سب تیرے ذہن میں مستحضر ہو جاتی ہیں اور تُو فوراً سمجھ جاتا ہے کہ کن مواقع پر یہ حکم
چسپاں ہوتا ہے اور کن مواقع پر چسپاں نہیں ہوتا.غرض رسول کریم ملایم کو اللہ تعالیٰ نے علم خارجی کے علاوہ علم اندرونی بھی بخشا تھا اور آلخر
نَشْرَحْ لَكَ صَدرَكَ کے معنے یہی ہیں کہ کیا علاوہ قرآن شریف کے ہم نے تجھے علم اندرونی
نہیں بخشا اور تیرے سینہ کو کھول نہیں دیا ؟
شرح کے معنے پھاڑنے اور ہل چلانے کے بھی ہوتے ہیں.ان معنوں کے رُو سے
آیت کا یہ مطلب ہوگا کہ اے محمد رسول اللہ صلیم کیا ہم نے تیرے سینہ میں قرآن اُگانے کے
لئے ہل چلائے ہیں یا نہیں ؟ جس طرح مادی اشیاء کے لئے مناسب حال زمین کو تلاش کیا جاتا
800
Page 809
ہے اسی طرح ہم اپنے قرآن کے لئے اسی زمین میں ہل چلا سکتے تھے جو قرآن کے مناسب حال
ہو.سو ہمیں وہ مناسب حال زمین تیرا سینہ دکھائی دیا اور ہم نے اس میں ہل چلا دیا.اب دنیا
دیکھے گی کہ اس میں سے کیسے شاندار پھل پیدا ہوتے ہیں.جب خدا تعالیٰ جیسا بیج بونے والا ہو،
خدا تعالیٰ جیسا ہل چلانے والا ہو اور محمد علی ایم کے سینہ جیسی زمین ہو تو اس کھیتی کی برتری کا کون
انکار کر سکتا ہے.غرض الم نشرح لك صدرك کے ایک معنے یہ ہیں کہ قرآن کریم کے نزول کے علاوہ
رسولکریم علی کواللہ تعالے کی طرف سے ایسا علم لدنی بخشا گیا تھا کہ اس کے ذریعہ آپ
ہر علم کو فوراً قبول کر کے اس کی وسعتوں کے انتہا تک پہنچ جاتے تھے اور اس سے استنباط اور
تفقہ کر کے مسلمانوں کو علم دین سکھاتے.رسول ریم ملایم کے رضاعی رشتہ داروں کی طرف سے روایت آتی ہے کہ بچپن میں
جب آپ کو حلیمہ دائی پرورش کے لئے لے گئی تو ایک دن جبکہ آپ باہر کھیل رہے تھے آپ کا
ایک رضاعی بھائی گھبراہٹ کی حالت میں دوڑا ہوا اپنی والدہ اور والد کے پاس آیا اور اس نے
کہا...کہ ہمارے بھائی پر کسی نے حملہ کر کے اسے ماردیا ہے.حلیمہ دوڑتی ہوئی باہر گئی تو
اس نے دیکھا کہ رسول کریم علیم اٹھ کر بیٹھے ہوئے ہیں.حلیمہ نے آپ سے دریافت کیا کہ
بتاؤ کیا ہوا تھا؟ رسول کریم علیم نے جواب دیا کہ تین آدمی آئے تھے.انہوں نے میرا سینہ
چیرا اور میرے دل کو دھو کر اندر رکھ دیا اور پھر چلے گئے.روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ کے
سینہ پر اس کا ایک نشان بھی تھا.(سیرت الحلبیہ جز اوّل)
بعض دوسری روایتوں میں جو واقعہ معراج کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں ان میں بھی ذکر آتا ہے
کہ ایک فرشتہ آیا اس نے آپ کے سینہ کو چیر کر دل نکالا ، آلائش صاف کی اور پھر دوبارہ اسے
آپ کے سینہ میں رکھ دیا (روض الانف جز اول).( غیر احمدی ) مسلمان اس کو جسمانی معجزہ کے طور پر پیش کرتے ہیں.لیکن جہاں تک
801
Page 810
میں سمجھتا ہوں جس رنگ میں مسلمان اس واقعہ کو پیش کرتے ہیں اگر وہ زیادہ غور سے دیکھتے تو
یہ آپ کی شان کو بڑھانے والے معجزہ کی بجائے آپ
کی تنقیص کرنے والا معجزہ بن جاتا ہے.اول تو یہ سوال ہے کہ دل پر کونسی مادی آلائشیں ہوتی ہیں جنہیں صاف کرنے کی ضرورت
ہوتی ہے؟ جولوگ جنوں اور بھوتوں کے قائل ہیں وہ بھی اتنی معقولیت سے کام لیتے ہیں کہ کہتے
ہیں کہ فلاں جن نے فلاں کا دیکھتے ہی کلیجہ کھا لیا.وہ جنات کی ماہیت کے لحاظ سے سمجھتے ہیں
کہ انہیں چیر نے پھاڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی یونہی دیکھتے اور دوسرے کا کلیجہ نکال کر چبا
جاتے ہیں.اگر جنات کے متعلق بعض نہایت ضعیف العقیدہ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ سمجھتے
ہیں جن پیٹ چیرنے کے محتاج نہیں ہوتے تو فرشتوں کے متعلق کیوں یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ وہ
چیرنے پھاڑنے کے محتاج ہیں.اگر دل بنانے کے لئے فرشتے کسی کا پیٹ پھاڑنے کے
محتاج نہیں.اگر پھیپھڑا بنانے کے لئے وہ کسی کا پیٹ پھاڑنے کے محتاج نہیں.اگر جگر اور
معدہ بنانے کے لئے وہ کسی کا پیٹ پھاڑنے کے محتاج نہیں.اگر تلی بنانے کیلئے وہ کسی کا
پیٹ پھاڑنے کے محتاج نہیں.اگر دماغ بنانے کے لئے وہ کسی کا سر پھاڑنے کے محتاج
نہیں تو وہ دل کو صاف کرنے کے لئے کسی کا سینہ چاک کرنے کے کیوں محتاج ہو گئے ؟ جس
طرح وہ پیٹ چیرے بغیر انسان کے اندر گھس گئے تھے اور انہوں نے دل اور دماغ اور معدہ
اور جگر وغیرہ بنا دیا اسی طرح وہ سینہ کو چیرے بغیر رسول
کریم علی اللہ کا ول بھی صاف کر سکتے تھے.پھر سوال یہ ہے کہ آیا فرشتوں کو چھریوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ قرآن کریم سے معلوم ہوتا
ہے کہ انسانوں، پہاڑوں ، دریاؤں اور دوسری سب چیزوں کے بنانے میں خدا تعالیٰ کے
ملائکہ بھی ایک علت کے طور پر کام کرتے ہیں مگر جب وہ پہاڑ اور دریا وغیرہ بناتے ہیں تو نہ
انہیں ہتھوڑوں کی ضرورت ہوتی ہے نہ آری کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کدالوں کی ضرورت ہوتی
ہے.وہ بغیر ان مادی ہتھیاروں کے یہ تمام کام سر انجام دے دیتے ہیں.پھر وجہ کیا ہے کہ اور
جگہ تو انہیں کسی ہتھیار کی ضرورت نہیں پڑتی مگر رسول کریم علی ایم کے دل کی صفائی کے لئے
802
Page 811
جب ان کو آنا پڑا تو وہ چھری بھی اپنے ساتھ لے آئے جس سے انہوں نے رسول کریم علی ایم کا
سینہ چاک کیا.پس یہ روایت عقل کے بالکل خلاف ہے.کروڑوں کروڑ کام دنیا میں فرشتے کرتے ہیں مگر
کبھی اس رنگ میں انہوں نے اپنے فرائض کو سر انجام نہیں دیا.پس اگر یہ مان بھی لیا جائے
کہ عملی طور پر ایسا ہوا تھا تب بھی اس کے لئے پیٹ کو چاک کرنے کی ضرورت تسلیم نہیں کی
جاسکتی.اور نہ چھریوں کی حاجت تسلیم کی جاسکتی ہے.درحقیقت اس غلطی کی بنا یہ ہے کہ اسلامی تعلیم کے بالکل خلاف یہ خیال کرلیا گیا ہے کہ
فرشتے ان مادی اشیاء کے محتاج ہوتے ہیں.حالانکہ یہ بات ایسی ہے جس کو دوسرے مقامات
پر خود مسلمان ہی تسلیم نہیں کرتے.حدیثوں میں صاف طور پر ذکر آتا ہے کہ جب جنین رحم مادر
میں ہوتا ہے تو فرشتہ ماں کے پیٹ میں جاتا اور اس میں زندگی کی روح پھونک دیتا ہے.مگر کیا
کسی نے دیکھا ہے کہ کبھی عورت کا پیٹ فرشتوں نے چاک کیا ہو؟ وہ خود تسلیم کرتے ہیں کہ
بیشک سب کام فرشتے کرتے ہیں مگر وہ پیٹ چاک کرنے کے محتاج نہیں ہوتے.جب وہ
وہاں چھریوں کی ضرورت تسلیم نہیں کرتے تو اس واقعہ کو کیوں ظاہری شکل دی جاتی ہے اور
کیوں رسول کریم عالم کا سینہ ظاہری طور پر چاک کیے جانے پر زور دیا جاتا ہے؟
ہم مانتے ہیں کہ فرشتوں نے آپ کا سینہ چاک کیا اور ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ انہوں
نے آپ کے دل کی صفائی کی مگر ہم ساتھ ہی یہ بھی مانتے ہیں کہ انہوں نے اسی طرح آپ کا
سینہ چاک کیا اور اسی طرح آپ کا دل نکال کر دھو یا جس طرح وہ جگر بناتے ہیں، تلی بناتے
ہیں، دل اور پھیپھڑ بناتے ہیں.جس طرح وہاں وہ انسان کا دل اور جگر بناتے ہیں.اسی طرح
یہاں بھی انہوں نے رسول کریم علیم کا دل نکالا.اس میں کوئی حرج نہیں اور یہ بات ایسی
ہے جسے ہم بھی تسلیم کرتے ہیں.حقیقت یہ ہے کہ رسول کریم صلیم نے یہ ایک کشف دیکھا تھا اور کشفی نظارہ بعض دفعہ
803
Page 812
دوسرے لوگ بھی دیکھ لیتے ہیں.ساری غلطی مسلمانوں کو اس وجہ سے لگی ہے کہ حلیمہ کے بیٹے
نے بھی یہ واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا.وہ کہتے ہیں اگر یہ ظاہری واقعہ نہیں تھا تو حلیمہ کے
بیٹے نے کس طرح دیکھ لیا ؟ حالانکہ اگر صحابہ جبرائیل کو دیکھ سکتے ہیں تو حلیمہ کا بیٹا رسول کریم
سلام کے اس کشفی واقعہ کو کیوں دیکھ نہیں سکتا.رض
حدیثوں میں آتا ہے کہ ایک شخص رسول کریم بیلی کے پاس آیا اور اس نے آپ سے
مختلف سوالات کئے جن کے آپ نے جوابات دیے.جب وہ چلا گیا تو رسول کریم مال لا میں نے
صحابہ سے پوچھا جانتے ہو یہ کون تھا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ! ہمیں تو معلوم نہیں.خدا اور
اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں.رسول کریم علی علیہ نے فرمایا یہ جبرائیل تھا جو تمہیں علم سکھانے
کے لئے آیا.اب دیکھو جبرائیل رسول کریم علی ایم کے پاس آیا مگر صحابہ نے بھی دیکھ لیا.پس کئی ایسے
کشفی نظارے ہوتے ہیں جن میں ساتھ کے لوگ بھی شریک ہو جاتے ہیں.مگر اس کے یہ معنے
نہیں ہوتے کہ وہ مادی واقعہ ہوتا ہے.پھر معلوم نہیں وہ صرف چھری کو مادی کیوں قرار
دیتے ہیں.فرشتے کو بھی کیوں مادی نہیں سمجھ لیتے.مگر وہ فرشتے کو تو روحانی قرار دیتے ہیں اور
چھری کو مادی قرار دیتے ہیں.اگر آدھی روحانی چیز تھی تو آدھی ماڈی کیوں ہو گئی ؟
وہ کہتے ہیں اس واقعہ کے مادی ہونے کا ایک ثبوت یہ ہے کہ رسول کریم ملایم کے سینہ
پر اس کا نشان تھا.ہم کہتے ہیں اگر نشان تھا تب بھی یہ اس واقعہ کے مادی ہونے کا ثبوت
نہیں.حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو خدائے تعالیٰ نے ایک نشان دکھایا جس کے
نتیجہ میں آپ کے کپڑوں پر سرخ روشنائی کے بعض نشانات آگئے مگر اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ
یہ ظاہری واقعہ تھا.تھا تو یہ کشفی واقعہ مگر اللہ تعالیٰ نے اس کشف کی صداقت کے لئے ظاہر میں
بھی روشنائی پیدا کر دی یہ بتانے کے لئے کہ میں قادر مطلق خدا تمہیں یہ نظارہ دکھا رہا ہوں.پس
گو یہ واقعہ مادی نہیں تھا مگر اللہ تعالیٰ نے ظاہر میں اس کا نشان پیدا کر دیا.اس طرح اگر
804
Page 813
رسول کریم علیم کے سینہ پر نشان تھا تو اس کے یہ معنے نہیں ہیں کہ یہ ظاہری واقعہ تھا.یا
ظاہر میں انسانی قلب پر کوئی میل ہوتی ہے جسے دھونے کی ضرورت ہوتی ہے.غرض یہ غلط
ہے کہ یہ ایک ظاہری واقعہ تھا جو رسول کریم ملایم کے ساتھ گزرا.یہ ظاہری واقعہ نہیں بلکہ ایک کشف تھا جو رسول کریم علیم کو دکھایا گیا.ہاں اللہ تعالیٰ
نے آپ کی عظمت کے اظہار کے لئے اور آپ کے رضاعی خاندان کے دل میں آپ کی محبت
پیدا کرنے کے لئے ایسا تصرف کیا کہ حلیمہ کے بیٹے نے بھی اس واقعہ کو دیکھ لیا.اور اس کی
گواہی سے سب پر یہ اثر ا ہوا کہ یہ غیر معمولی واقعہ بتا رہا ہے کہ یہ لڑکا ایک دن بہت بڑی
عظمت اور شان حاصل کرے گا.پھر یہ بتانے کے لئے کہ یہ کشف واقعہ میں ہم نے دکھایا تھا
اللہ تعالیٰ نے آپ کے سینہ پر بھی نشان پیدا کر دیا تا کہ سب لوگ اللہ تعالیٰ کے اس نشان کے
گواہ رہیں.جیسے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے گرتے پر سرخ روشنائی کے قطرات
اللہ تعالیٰ نے اس لئے ڈالے تا کہ اور لوگ بھی اس نشان کے گواہ رہیں.گومعتبر روایتوں میں یہ
ذکر نہیں آتا کہ رسول کریم میایم کے سینہ پر نشان تھا.مگر ہمیں اس کو تسلیم کرنے سے انکار کی
خاص ضرورت نہیں.اگر روشنائی کے نشان اللہ تعالیٰ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے
کپڑوں پر پیدا کر سکتا ہے تو اس کشف کی تصدیق کے لئے اگر اللہ تعالی نے رسول کریم علایم
کے سینہ پر کوئی نشان پیدا کر دیا ہو تو اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں.پس جس حد تک اس واقعہ کو کشفی ماننے کا تعلق ہے ہمیں اس کی صحت سے ہرگز
انکار نہیں.لیکن جس حد تک اس واقعہ کو ماڈی قرار دینے کا سوال ہے ہمارے نزدیک یہ بات
عقل کے خلاف ہے.ورنہ جیسا کہ احادیث میں آتا ہے ماننا پڑے گا کہ جب کوئی شخص بُرا
کام کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ نشان پڑ جاتا ہے اور جب اچھا کام کرتا ہے تو اس کا دل اعلیٰ
حالت میں رہتا ہے.حالانکہ یہ بات واقعات کے خلاف ہے.نعشوں کو چیر نے پھاڑنے
اور مختلف امراض کے نتیجے میں انسانی جسم میں جو تغیرات واقع ہوتے ہیں ان کو دیکھنے بھالنے کا
کام اس زمانے میں بہت ترقی پر ہے.لاکھوں نعشیں اب تک چیری جاچکی ہیں اور
805
Page 814
تشریح الابدان کے ماہرین نے ان تمام تغیرات کا پوری طرح جائزہ لے لیا ہے جو امراض کے
نتیجے میں انسانی جسم میں واقع ہوتے ہیں.اگر اس نظریہ کو درست تسلیم کر لیا جائے کہ برے کام
کے نتیجے میں قلب پر مادی شکل میں سیاہی چھا جاتی ہے اور اچھے کام کرنے کے نتیجہ میں قلب پر
مادی شکل میں نور آجاتا ہے تو کئی مسلمانوں کو کافر اور کئی کافروں کو مسلمان قرار دینا پڑے گا.وہ
مسلمان جو دم گھٹ کر مر جاتے ہیں ان کے دل یقینا کالے ہوں گے اور وہ ہندو اور سکھ جن کے
تنفس پر بیماری کا اثر نہیں ہوتا ان کے دل یقینا اچھی حالت میں ہوں گے.ایسی حالت میں ہمیں
روزانہ کافروں کو مسلمان اور مسلمانوں کو کافر قرار دینا پڑے گا اور یہ حقیقت کے خلاف ہے.در حقیقت رسول کریم مالی نے جو کچھ دیکھا وہ ایک کشف تھا.کشفی حالت میں فرشتہ آپ
کے پاس آیا اور اس نے آپ کا سینہ چاک کر کے آپ کا دل نکالا اور اسے دھودھا کر پھر اندر
رکھ دیا.بیشک ظاہر میں اس واقعہ کو تسلیم نہیں کیا جاسکتا مگر خواب یا کشف کی حالت میں اس
قسم کے واقعہ کو تسلیم کرنا ہر گز بعید از قیاس نہیں.غرض عام مسلمانوں کو تمام دھو کا کشف کی حقیقت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے لگا ہے ورنہ کشفی
حالت میں دل پر سیاہی بھی دیکھی جاسکتی ہے اور کشفی حالت میں یہ بھی دیکھا جاسکتا ہے کہ دل میں
نور بھر دیا گیا ہے.فرق صرف یہ ہوگا کہ اگر جھوٹی خواب ہو تو گو انسان بہت کچھ دیکھتا ہے مگر
اسے ملتا کچھ نہیں.لیکن اگر خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی خواب دکھایا جائے تو فوراً انسان کو اس
کے مطابق اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام بھی مل جاتا ہے.قادیان میں ایک دفعہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ مرزا صاحب کو بھی بے شک الہام
ہوتا ہے کہ تجھے ہم نے بڑا درجہ دیا ہے مگر مجھے بھی خدا تعالیٰ روزانہ کہتا ہے کہ تو موسیٰ ہے، توعیسی
ہے، تو محمد ہے.لوگوں نے اسے بہت کچھ سمجھایا مگر وہ نہ مانا.آخر کسی نے حضرت مسیح موعود
علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اس کا ذکر کر دیا.حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے
فرمایا اسے ہمارے پاس لاؤ یا آپ نے فرمایا اس سے سوال کرو ( مجھے اس وقت اچھی طرح یاد
نہیں ) کہ جب خدا تم سے کہتا ہے کہ تم عیسی ہو تو کیا عیسی کی طرح تمہیں خلق طیر کا نشان بھی ملتا
806
Page 815
ہے یا تمہارے ہاتھ سے بھی اسی طرح مردے زندہ ہوتے ہیں جس طرح عیسی کے ہاتھ سے زندہ
ہوتے تھے یا جب خدا تمہیں موسیٰ کہتا ہے تو کیا موسیٰ کی طرح ید بیضا کا نشان بھی تمہیں عطا کرتا
ہے یا جب محمد کہتا ہے تو کیا محمدرسول اللہ علیہ کا وہ مقام جودَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنٍ أَوْ
آنلى(النجم 9-10) میں بیان کیا گیا ہے وہ بھی تمہیں ملتا ہے.یا تمہیں وہی فصاحت اور وہی
بلاغت عطا کی جاتی ہے جو رسول کریم علیم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئی ؟ وہ کہنے لگا ملتا
تو کچھ نہیں.حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو پھر وہ خدا نہیں بلکہ شیطان ہے
جو تمہیں روزانہ عیسی اور موسیٰ اور محمد کہتا ہے.اگر خدا تمہیں یہ مقام عطا کرتا تو تمہیں اس مقام سے
تعلق رکھنے والے انعامات بھی دیتا.اسی طرح ایک دوسرا شخص بھی دیکھ سکتا ہے کہ اس کا
سینہ چیرا گیا اور دل دھو کر دوبارہ اس کے اصل مقام
پر رکھ دیا گیا.مگر فرق یہ ہوگا کہ اس کا سینہ
پھر بھی تنگ ہی رہے گا.مگر جس کا خدا دل دھو کر اس کے سینہ میں رکھ دے گا اس کا سینہ پہلے
سے ہزاروں گنا زیادہ وسیع ہو جائے گا.چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق آپ
کے رضاعی بھائی نے جو شہادت دی اگر وہ بات جھوٹی ہوتی تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کا شرح
صدر ہو کس طرح گیا؟ پھر تو چاہئے تھا آپ کا شرح صدر نہ ہوتا.مگر ہم دیکھتے ہیں کہ ادھر آپ کا
سینہ چاک کر کے دل دھویا گیا اور ادھر دنیا نے دیکھ لیا کہ ہر علم وفن کے متعلق رسول کریم ملالیم
نے تعلیمات دیں جن کی نظیر اور کسی شخص میں نہیں ملتی.علم کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جس میں قرآنی
خیالات لے کر آپ نے ری فلسیکٹر کے طور پر دنیا میں نہایت اعلیٰ اور بے عیب تعلیمیں پیش نہ
کی ہوں.جب ہم ان واقعات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ آپ کا سینہ چیرنے والا
فرشتہ ہی تھا ورنہ خالی دل دھودھا کر سینہ کے اندر رکھ دینے میں کیا کمال ہو سکتا تھا.بات تو وہی
رہی پہلے بھی دل میں خون آتا تھا اور اس کے بعد بھی دل میں خون نے ہی آنا تھا.جو چیز اس واقعہ کو عظمت دیتی ہے وہ اس کا جسمانی نہیں بلکہ روحانی پہلو ہے.اسی کی
طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا الم نشرح لك صدرك.کیا بچپن میں ہی ہم نے یہ نظارہ
تجھے نہیں دکھا دیا تھا اور ہم نے بچپن میں ہی تجھ سے یہ نہیں کہہ دیا تھا کہ ہم ایک دن تجھ میں
807
Page 816
بڑے بڑے کمالات پیدا کردیں گے؟ یہ تعبیر ہے جو اس کشفی واقعہ کی تھی اور جس نے بعد میں
آپ کی صداقت کو آفتاب نیم روز کی طرح ظاہر کر دیا.ورنہ ہم یہ ماننے کے لئے تیار نہیں کہ
نعوذ باللہ آپ کے دل پر سیاہی تھی جسے فرشتوں نے دھودیا.آپ کا دل پہلے بھی پاک تھا.اس
کو دھونے کے معنے یہ تھے کہ ہم نے نئی قابلیتیں اور علوم کی نئی وسعتیں تیرے اندر پیدا کردی
ہیں.یہ مطلب نہیں تھا کہ آپ کے دل پر نعوذ باللہ کوئی گند لگا ہوا تھا جسے انہوں نے دھودیا.ایک معنے اس آیت کے یہ بھی ہیں کہ ہم نے تیرے اندر قوت برداشت پیدا کردی
ہے.چنانچہ شرح صدر کے الفاظ اسی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ کسی چیز پر آپ کو تنگی نفس پیدا
نہیں ہوتی تھی بلکہ جو بات آتی آپ اس کو برداشت کر لیتے اور کہتے
هر چه از دوست می رسد نیکو است
آپ جانتے تھے کہ میرے ساتھ جو معاملہ ہے وہ خاص قانون کے ماتحت ہے.میں
خدا تعالیٰ کے کامل تصرف کے ماتحت ہوں.میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوگا خواہ وہ بظاہر برا ہو
میرے لئے انجام کار اچھا ہوگا.اسی وجہ سے آپ مصائب اور مشکلات میں گھبراتے نہیں
تھے.پس اس آیت کے ایک یہ بھی معنے ہیں کہ تیرے اندر قوت برداشت کمال درجہ کی
پیدا ہوچکی ہے.یہ قوت برداشت جو آپ کے اندر نظر آتی ہے یہ ایک ایسی بے مثال چیز ہے جس کا نمونہ
ہمیں اور کہیں نظر نہیں آتا.آپ بیشک نصیحت بھی کرتے ،لوگوں کو ان کی برائیوں سے منع بھی
فرماتے اور ناراضگی کے موقع پر ناراضگی کا بھی اظہار فرماتے مگر طبیعت آپ کے قابو سے کبھی
باہر نہیں ہوتی تھی.پس آلَم نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ کے ایک معنے یہ ہیں کہ کیا ہم نے تیرے
سینہ کو وسیع نہیں کر دیا کہ تجھے گالیاں ملتی ہیں مگر تو ان کی پرواہ نہیں کرتا.دکھ دئیے جاتے ہیں مگر
تو ان کی کوئی اہمیت نہیں سمجھتا.تیرے اندر اس قدر قوتِ برداشت پیدا کردی گئی ہے کہ
دشمنوں کے لیے مقابلہ اور ان کے متواتر مظالم پر بھی تیرے پائے استقلال میں کوئی جنبش پیدا
نہیں ہوتی.808
Page 817
وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ
اور ( ایسا کرکے ) ہم نے تیرے (اس) بوجھ کو تجھ پر سے اتار دیا جس نے تیری کمر توڑ
رکھی تھی.اوِزُر کے معنے بوجھ کے ہیں.جس طرح پہلی آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعارت الشرح لی صدری کے
مقابل میں رسول کریم ملی تعلیم کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدُرَكَ اسى
طرح وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ میں ماضی کے الفاظ استعمال کر کے حضرت
موسیٰ علیہ السلام پر آپ کی ایک فضیلت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے.حضرت موسیٰ علیہ السلام
نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلی (طه 30) اے میرے رب میرے
اہل میں سے کوئی میرا بوجھ بٹانے والا پیدا کر دے.گویا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے
ایک ایسا شخص مانگنے کی ضرورت محسوس ہوئی تھی جو اُن کا بوجھ بٹانے والا ہو.مگر اللہ تعالیٰ
رسول کریم صلی اللہ سے فرماتا ہے کہ ہم نے بغیر تیرے مانگنے کے تجھے ایسے ساتھی عطا کر دیے
ہیں جو تیرے بوجھ کو صرف بٹانے والے نہیں بلکہ سارا بوجھ اپنے آپ اٹھانے والے ہیں.انہوں نے تیرے اوپر سے وہ سب کا سب بوجھ اٹھا لیا ہے جس نے تیری کمر کو توڑ دیا تھا.اسی مفہوم کی آیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارہ میں آتی ہے وہ دعا کرتے ہیں
وَاجْعَلْ لى وَزِيرا من اهلی اور اس کے معنے اختلافی نہیں مُسلّمہ ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام دشمنوں
کی مخالفت کے خیال سے فوراً ہی ایک مومن کا مطالبہ کرتے ہیں جو آپ کا بوجھ اٹھائے.آنحضرت صلم کی نسبت اللہ تعالیٰ خود فرما دیتا ہے کہ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي انْقَضَ
ظهرك...ہم نے تیرا بوجھ اتار دیا اور تیری مدد کے لئے وہ لوگ کھڑے کر دیئے جنہوں نے
تیرے بوجھ کے نیچے اپنے کندھے دے دیئے اور کہا یا رسول اللہ علیم ہم اس بوجھ کو اٹھانے
809
Page 818
کے لئے تیار ہیں.پس وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي انْقَضَ ظَهْرَكَ کے معنے یہ ہیں کہ وہ بوجھ جس نے
تیری کمر کو توڑ دیا تھاوہ ہم نے خود اٹھا لیا.تو نے اس کام کی طرف نگاہ کی اور حیران ہو کر کہا کہ
میں یہ کام کیونکر کروں گا.خدا نے ایک دن میں ہی تجھے پانچ وزیر دے دیئے.ابوبکر کا ستون
اس نے اسلام کی چھت قائم کرنے کے لئے کھڑا کر دیا.خدیجہ کا ستون اس نے اسلام کی
چھت قائم کرنے کے لئے کھڑا کر دیا علی کا ستون اس نے اسلام کی چھت قائم کرنے کے
لئے کھڑا کر دیا.زید کا ستون اس نے اسلام کی چھت قائم کرنے کے لئے کھڑا کر دیا.ورقہ
بن نوفل کا ستون اس نے اسلام کی چھت قائم کرنے کے لئے کھڑا کر دیا اور اس طرح وہ بوجھ جو
تجھ اکیلے پر تھا وہ ان سب لوگوں نے اٹھالیا.اس آیت کے ایک یہ معنے بھی ہیں کہ ہم نے تجھے ایسی تعلیم دی ہے جو آپ ہی آپ
دلوں کو موہ لیتی ہے.بعض تعلیمیں ایسی ہوتی ہیں جو بظاہر اچھی ہوتی ہیں مگر وہ ایسی فلسفیانہ
باتوں پر ر
مشتمل ہوتی ہیں کہ ان کا سمجھنا لوگوں کے لئے بڑا مشکل ہوتا ہے.وہی تعلیم ملک
میں فوری طور پر مقبولیت حاصل کر سکتی ہے جو سمجھنے میں آسان ہو اور جس میں ہر فطرت کو ملحوظ
رکھا گیا ہو.پس وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ میں ایک یہ بات بھی بیان کی
گئی ہے کہ تجھے اپنی تعلیم کا پھیلانا بڑا مشکل نظر آتا تھا مگر ہم نے اسے اس قدر دلکش اور اس قدر
جاذبیت رکھنے والی بنایا ہے کہ ہر طبقہ کے لوگ تیری طرف کچھچے چلے آتے ہیں.جو بھی پاکیزہ
فطرت رکھنے والا انسان اس تعلیم کو سنتا ہے فوراً کہہ اٹھتا ہے آمَنَّا وَصَدَّقْنَا.میں ایمان لایا
اور میں اس کی صداقت کو قبول کرتا ہوں.غرض فرماتا ہے وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ اے محمد رسول اللہ
ام کیا ہم نے تجھے یہ سامان نہیں بخشا کہ ایک طرف تجھے ہم نے ایسے ساتھی دیئے جنہوں
نے تیرا بوجھ اٹھالیا اور دوسری طرف ہم نے تجھے ایسی تعلیم دی جو خود بخود فطرت کے اندر نفوذ
810
Page 819
کرتی چلی جاتی ہے کوئی روک اس کی اشاعت میں حائل نہیں ہوتی.وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ
اور تیرے ذکر کو ہم نے بلند کر دیا.جب انبیاء علیہم السلام دعوی کرتے ہیں تو سارے ملک میں ان کے خلاف جوش پیدا
ہوجاتا ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں یہ تعلیم جو اُن کی طرف سے پیش کی جارہی ہے ایسی ہے کہ ایک
دن ضرور غالب آ جائے گی.یہی حال سچے دنیوی علوم کا ہوتا ہے کہ جب کوئی نئی تحقیق لوگوں
کے سامنے پیش کی جائے تو لوگ اس کی ضرور مخالفت کرتے ہیں.کیونکہ ان کے دلوں میں یہ ڈر
پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر ہم نے مخالفت نہ کی تو ہمارا نظریہ اس کے مقابلہ میں باطل ہو جائے گا.اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بعد میں صداقت کو بہر حال تسلیم کر لیا جاتا ہے.مگر ابتدا میں ایسا ہی
ہوتا ہے کہ لوگ مخالفت کرتے ہیں اور ہر قسم کی تدابیر سے سچائی کو کچلنے کی کوشش کی جاتی
ہے.اسی مخالفت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہم
نے تیر از کر بلند کر دیا ہے.یہاں ذکر کا بلند ہونا ماننے کے لحاظ سے نہیں بلکہ اس لحاظ سے ہے
کہ دنیا میں ہر جگہ تیر اذکر ہو رہا ہے چاہے اچھے رنگ میں ہو یا برے رنگ میں.تعریف کے
رنگ میں ہو یا مذمت کے رنگ میں.بہر حال ہر مجلس اور ہر محفل اور ہر گھر اور ہر خاندان میں
تیرا نام بلند ہو رہا ہے.اور ایک شور ہے جو تیری وجہ سے برپا ہے.غرض رسول کریم ملی ایم کی مخالفت کا ایک سلسلہ تھا جو ہر مجلس اور ہر خاندان میں جاری تھا.جہاں بھی دیکھو یہی ذکر ہوتا تھا کہ محمد عبای شمالی نے بہت بڑا فتنہ پیدا کر دیا ہے.اس فتنہ کے
سد باب کے لئے اب ہمیں کیا کرنا چاہئے.مخالفت کا یہ جوش و خروش اور رسول کریم علی ایم کی تذلیل
کی یہ کوششیں ثبوت تھیں اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ
کی تعلیم میں ایسی کشش رکھی تھی کہ دنیا
سمجھتی تھی اس کا ہمارے ساتھ ٹکراؤ ہماری تباہی اور بربادی کا موجب بننے والا ہے....اللہ تعالیٰ اس
آیت میں فرماتا ہے کہ ہمارا تجھ پر کتنا بڑا احسان ہے کہ آج ہر مجلس میں
تیر از کر ہورہا ہے.811
Page 820
پس وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكرك کے ایک معنے یہ ہیں کہ ہم نے تیرے ذکر کو اس قدر بلند
کردیا ہے کہ ہر مجلس اور ہر نادیہ میں تیرا ذ کر ہونے لگا ہے.لوگوں کی طبائع میں ایک ہیجان
پیدا ہوگیا ہے اور وہ اس بات پر مجبور ہو گئے ہیں کہ تیری طرف توجہ کریں.اس کا نتیجہ تیرے حق
میں لازماً اچھا ہوگا کیونکہ لوگ جب غور کریں گے تو ان پر تیری صداقت واضح ہو جائے گی.اس آیت کے ایک یہ بھی معنے ہیں کہ ہم نے تیری قبولیت دنیا میں پھیلا دی ہے.در حقیقت کامیابی کے ساتھ اس امر کا بھی تعلق ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں قبولیت
کے آثار پیدا کر دئیے جائیں.حدیثوں میں آتا ہے جب خدا تعالیٰ اپنے کسی بندے کو اپنی
محبت کے لئے منتخب فرماتا ہے تو اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ میں نے فلاں شخص کو چن لیا
ہے تم بھی اس سے محبت کرو اور لوگوں کے دلوں میں اس کی قبولیت پیدا کرو.چنانچہ آہستہ
آہستہ تمام دنیا میں اس کی قبولیت پیدا ہو جاتی ہے.یہ معنی بھی اس آیت کے ہیں.فرماتا ہے
که گو یہ لوگ تیری مخالفت کرتے ہیں مگر ساتھ ہی تیری بڑائی اور عظمت کو بھی تسلیم کرتے ہیں.حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جب وفات ہوئی تو کئی غیر احمدیوں اور ہندوؤں نے
مضامین لکھے جن میں انہوں نے آپ کی بڑائی اور عظمت کا ذکر کیا.اس سے معلوم ہوتا ہے کہ
گو وہ ظاہر میں آپ کی مخالفت کرتے تھے مگر ان کے دل آپ کی عظمت کے قائل تھے.یہ
قبولیت اور عظمت کسی مفتری انسان کو کبھی حاصل نہیں ہوسکتی.پس فرماتا ہے دنیا میں
مخالفتیں کرنے والے مخالفتیں کرتے ہیں مگر ان کی مخالفت کا پہلو یکطرفہ ہوتا ہے.یہ نہیں ہوتا
کہ وہ کسی کی مخالفت کے ساتھ اس کی عظمت کے بھی قائل ہیں.مگر یہاں یہ حالت ہے کہ یہ
لوگ تیرے دشمن بھی ہیں اور تیری طاقت اور عظمت کے بھی قائل ہیں.کہتے ہیں کہ تو بڑا جھوٹا
ہے مگر ساتھ ہی کہتا ہے کہ تو بڑا امین ہے.سنے والا سنتا ہے تو حیران ہوتا ہے کہ یہ کیا متضاد
باتیں کہہ رہے ہیں.ایک کہتا ہے وہ شاعر تو ہے مگر شعر نہیں کہتا یا کا ہن تو ہے مگر کاہنوں کا
دشمن ہے.گویا جہاں وہ الزام لگاتے ہیں وہاں ساتھ ہی ایک رنگ میں عظمت اور نیکی کا بھی
812
Page 821
اقرار کر جاتے ہیں.اس کے علاوہ اس آیت کا اشارہ اس طرف بھی ہے کہ محمد رسول الله عالی لیلی
کا ذکر پھیلنا شروع ہو جائے گا.فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا
پس ( یاد رکھو کہ ) اس تنگی کے ساتھ ایک بڑی کامیابی ( مقدر ) ہے (ہاں) یقیناً اس تنگی
کے ساتھ ایک (اور بھی) بڑی کامیابی ( مقدر ) ہے.عربی قواعد کی رُو سے تنوین ہمیشہ بڑائی اور عظمت کے اظہار کے لئے آتی ہے.پس
اس آیت کے معنے یہ ہیں کہ یقیناً اس تنگی کے ساتھ ایک بہت بڑی آسانی ہے.ہاں ہاں یقینا
اس تنگی کے ساتھ ایک بہت بڑی آسانی ہے.گویا اصل مقصد تنگی کا ذکر کرنا نہیں بلکہ اصل
مقصد یسر کی بڑائی اور اس کی اہمیت پر زور دینا ہے.لیکن بعض نحوی کہتے ہیں کہ آیت میں بیشتر ا کا نکرہ کا استعمال اور پھر اس کا تکرار بتارہا ہے
کہ یہاں ایک نہیں بلکہ دو ٹیسر مراد ہیں.بے شک حسر ایک ہی ہے مگر ٹیسر دو ہیں.ان کے
نزدیک اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ یقیناً اس تنگی کے ساتھ ایک بہت بڑی آسانی ہے.یقیناً
اس تنگی کے ساتھ ایک اور بھی بہت بڑی آسانی ہے.گویا نکرہ کا تکرار اس امر پر دلالت کرتا
ہے کہ کیسر دو ہیں اور کیسر کی تنوین بتاتی ہے کہ ہر ٹیسر بہت بڑی شان کا ہے.ان دوسرے معنوں کی احادیث سے بھی تائید ہوتی ہے.چنانچہ رسول کریم علی یہ ایک دفعہ ہنستے
ہوئے اپنے گھر سے باہر تشریف لائے اور فرمایا میں نے دیکھا ہے کہ عسر ٹیسر کے پیچھے دوڑا چلا
جارہا ہے.پھر آپ نے فرمایا ایک عسر دو ئیسر پر غالب نہیں آسکتا.اس سے معلوم ہوتا ہے کہ
کشفأ رسول کریم معلم کو اس آیت کا یہی مفہوم سمجھایا گیا ہے کہ ٹیسر دو ہیں اور غسر ایک ہے.اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ دو ٹیسر کون سے ہیں جن کا اس آیت میں ذکر آتا ہے.اس کا جواب یہ ہے کہ انسان کو پورے طور پر اسی وقت سکون حاصل ہوتا ہے جب ذہنی اور
خارجی طور پر دونوں لحاظ سے اسے اطمینان کے سامان میسر ہوں.813
Page 822
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ہمارے رسول ! بیشک آج دنیا تیرے ساتھیوں کو سخت سے سخت
تکالیف پہنچارہی ہے مگر ہم عنقریب ان کو دونوں قسم کے اطمینان دینے والے ہیں.پہلا
اطمینان جوان کو میسر آئے گاوہ ذہنی ہو گا.یعنی تیری جماعت کا ہر فرد ذہنی لحاظ سے اس بات پر
مطمئن ہوگا کہ اس نے سچائی کو قبول کیا ہے، راستی کو اختیار کیا ہے، نجات کے طریق کو پسند
کیا ہے.یہ خلش اور ڈبدہ اس کے اندر نہیں ہوگا کہ نہ معلوم جس راہ پر میں چل رہا ہوں وہ خدا
تک انسان کو پہنچاتا ہے یا نہیں پہنچا تا.اس کے بعد خارجی لحاظ سے بھی ہم ان کے اطمینان
کے سامان پیدا کردیں گے یعنی دشمن کی تکالیف کا سلسلہ جاتا رہے گا.ان کو کامیابی حاصل
ہو جائے گی اور و تنگی جو آج محسوس کی جارہی ہے بالکل دور ہو جائے گی.گویا وہ دو ٹیسر ہیں جن
کی طرف اس آیت میں اشارہ کیا گیا ہے.وہ ذہنی اور خارجی اطمینان کے سامان ہیں.یعنی
ہم قوم کو با ایمان بنانے کے لئے اس کے تمام شکوک وشبہات کو مٹا کر اسے یقین کی ایک
مضبوط چٹان پر کھڑا کر دیں گے اور خارجی لحاظ سے ان تمام مصیبتوں اور تکلیفوں کو دور کر دیں
گے جو دشمن کی طرف سے انہیں پیش آرہی ہیں اور وہ غالب اور بادشاہ ہو جائیں گے جس کی وجہ
سے کوئی انہیں جسمانی عذاب نہ دے سکے گا.دوسرے معنے دنیوی اور اخروی انعامات کے ہیں.یعنی تمہیں دنیا کے بھی انعامات ملیں
گے اور آخرت کے انعامات بھی تمہیں عطا کئے جائیں گے.اگر کوئی کہے کہ اُخروی انعامات
کے ملنے کا کیا ثبوت ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ رؤیا و کشوف اور الہامات جن سے اللہ تعالیٰ
کے مومن بندے اس دنیا میں اپنی استعداد کے مطابق حصہ لیتے ہیں وہ اس بات کا ثبوت ہوتے
ہیں کہ اللہ تعالی کی طرف سے اخروی نعماء کے متعلق جو کچھ کہا جارہا ہے وہ بالکل درست ہے.حمد اس آیت کے یہ بھی معنی ہیں کہ جب کبھی اسلام پر تنگی اور مصیبت کا زمانہ آئے گا
اللہ تعالیٰ اس کے بعد ترقی کا ایک نیا دور پیدا کر دیا کرے گا.گویا اسلام کے ایک دفعہ قائم ہو
جانے اور اس کے ہلاکت سے بچ جانے کے بعد ہر موقع پر اس کی ترقی کے نئے سے نئے
814
Page 823
سامان پیدا ہوتے رہیں گے.ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ اسلام ہمیشہ کے لئے مغلوب ہوجائے اور
کفر کو غلبہ حاصل ہو جائے.گویا حفاظت اسلام کا وعدہ کرتے ہوئے مسلمانوں کو بشارت دی
گئی ہے کہ خدا تعالیٰ کی تائید ہمیشہ اس مذہب کے ساتھ ہوگی اور وہ ہمیشہ تنزل کے بعد اس کی
ترقی کے سامان پیدا کرتا رہے گا.دو کے لفظ کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس
آیت میں بعثت محمدی اور بعثت احمدی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور فرمایا گیا ہے کہ اس
زمانے میں کفر نے خاص جوش مارا ہے مگر ہم اس کفر کو توڑنے کے لئے محمد رسول عالم کی
دو روحانی بعثتیں کریں گے تا اس کا زور بالکل ٹوٹ جائے.فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ
پس جب ( بھی ) تو فارغ ہو تو ( دوسرے مقصد کے حصول کے لئے ) پھر کوشش میں
لگ جا.فرغ کے کئی معنی ہوتے ہیں.جب فرغ مِنَ الْعَمَلِ کہیں تو اس کے معنی ہوتے ہیں
خَلا ذَرْعَہ وہ کسی کام سے فارغ ہو گیا اور جب فَرغَ لَهُ وَالَيْهِ کہیں تو معنی ہوتے ہیں قَصَدَ
اس نے کسی چیز کا ارادہ کیا.نیز کہتے ہیں فَرَغَ فُلانٌ فَرُوعًا اور مراد یہ ہوتی ہے کہ مات.فلاں شخص مر گیا.اور جب برتن کے لئے فرغ کا لفظ بولیں تو اس کے معنی ہوتے ہیں کھلا.خالی
ہو گیا.نیز فرغ کے معنی کسی کام کو پورا کر دینے کے بھی ہوتے ہیں.چنانچہ کہتے ہیں فرغ
فلان من الشّيئي: اتمے کہ فلاں نے کام کو ختم کر دیا ( اقرب)
فَانْصَبْ نَصِبَ يَنْصَب سے امر کا صیغہ ہے اور نَصِبَ الرّجُلُ نَصْبا کے معنی ہوتے
ہیں آغیا.وہ تھک گیا.اور نصب فی الآمر کے معنی ہوتے ہیں جدو اجتہد اس نے محنت اور
کوشش کی ( اقرب) یہاں فانصب کے معنی محنت اور جد وجہد کرنے کے ہیں.اللہ تعالیٰ
فرماتا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَب جب تو فارغ ہو جائے تو پھر جد و جہد میں مشغول ہو جا.م یہاں ایک عجیب بات بیان کی گئی ہے.بظا ہر فراغت کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ
مشکل دُور ہوگئی اور کام ختم ہو گیا.مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تو فارغ ہو جائے تو پھر محنت میں
815
Page 824
مشغول ہو جا.پس سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب فارغ ہونے کے بعد بھی محنت میں ہی مشغول
رہنا ہے تو پھر فراغت کیسی ہوئی ؟
ما در حقیقت اس میں اسلام کی ترقی کے متعلق پیشگوئی کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ کتنا
بلند مقصد ہے جو ہم نے اپنے رسول کے سامنے رکھا ہے.بعض دفعہ دنیا میں یکدم کوئی تغیر پیدا
ہو جاتا ہے مگر وہ دیر پا نہیں ہوتا بلکہ جلد ہی رُو بہ زوال ہو جاتا ہے.لیکن بعض تغیرات ایسے
ہوتے ہیں جو گو تدریجاً پیدا ہوتے ہیں مگر ایک لمبے عرصہ تک دنیا کی کایا پلٹ کر رکھ دیتے
ہیں.اللہ تعالی محمد رسول اللہ علم کو فرماتا ہے کہ تیری ترقی گو تدریجی ہو گی مگر تیری
کوششوں کے نتائج مستقل اور دیر پا ہوں گے.پہلے ایک مشکل تمہارے سامنے آئے گی
اور جب تم اس کو ڈور کر لو گے اور اپنے پہلے مقام سے اونچے ہو جاؤ گے تو پھر دوسری مشکل پیش
آ جائے گی.اس وقت تمہارا فرض ہوگا کہ اس دوسری مشکل کو دور کرو اور اپنے مقام سے اور
اونچے ہو جاؤ.جب وہ مشکل بھی حل ہو گئی تو ایک تیسری مہم تمہارے سامنے آجائے گی اس وقت
تمہارا فرض ہوگا کہ اس تیسری مہم کو سر کرو اور اپنے مقام سے اور اونچے ہو جاؤ.گویا ایک دور
ہے جو چلتا چلا جائے گا اور غیر متناہی ترقیات ہیں جو تمہارے سامنے آتی چلی جائیں گی.کوئی
وقت اور کوئی لمحہ تمہاری زندگی میں ایسا نہیں آسکتا جب تم یہ خیال کرلو کہ میں اپنا کام ختم کر چکایا
میں نے جس بلندی پر پہنچنا تھا پہنچ گیا....چونکہ رسول کریم علیم کے سپر داللہ تعالی کی طرف
سے جو علمی اور عملی کام کیا گیا تھا اس کی کوئی انتہا نہیں تھی اس لئے اللہ تعالیٰ اس آیت میں آپ
کو مخاطب کر کے فرماتا ہے.اے محمد رسول اللہ ہم نے تیرے لئے کوئی محدود مقصود مقرر نہیں
کیا بلکہ غیر معمولی ترقیات کا دروازہ تیرے لیے کھولا گیا ہے.جب تو کسی ایک مہم کو سر کر لے تو
سمجھ لے کہ ابھی اس سے اوپر کی مہم کو تو نے سر کرنا ہے.اور جب دوسری مہم بھی سر ہو جائے تو
تو سمجھ لے کہ تیسری مہم تیرے سامنے کھڑی ہے اور تیرا فرض ہے کہ تو اس کو بھی سر کرے.غرض
تو نے بلندیوں کی طرف اپنے پورے زور کے ساتھ بڑھتے چلے جانا ہے اور کسی ایک مقام پر
816
Page 825
بھی اپنے قدم کو نہیں روکنا.گویا فَإِذَا فَرَغْمتَ فَانْصَب میں رسول کریم علیہ کے غیر متناہی
سفر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ آپ اپنے کام میں بڑھتے چلے جائیں گے اور
کوئی وقت ایسا نہیں آئے گا جب یہ کہا جا سکے کہ محمد رسول اللہ علیم اپنی منزل مقصود پر پہنچ
گئے اور اب وہ اپنے کام سے فارغ ہو گئے ہیں.اگر وہ ایک کام سے فارغ ہو جائیں گے تو
دوسرا کام شروع کر دیں گے.وَإلى رَبِّكَ فَارْغَبُ
اور تو اپنے رب کی طرف متوجہ ہو.فرماتا ہے اے محمد رسول اللہ صلی لیکن جب تم اس طرح چوٹیوں پر چڑھتے چلے آؤ گے تو
دیکھو گے کہ ہم آگے بیٹھے ہیں.ہم بلندیوں پر رہتے ہیں اور وہی ہمارے پاس آ سکتا ہے جو
غیر محدود جد و جہد سے کام لینے والا ہو.اس لئے ہماری ملاقات کے راستہ میں کسی مقام پر ٹھہرنا
نہیں بلکہ بڑھتے چلے آنا.ماخوذ از تفسير كبير زير تفسير سورة الانشراح)
817
Page 827
XXXXXXXX
بسمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَالتَّيْنِ وَالزَّيْتُونِ 3
وَطُورِ سِينِيْنة
وَهُذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ
لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي
أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ
ثُمَّ رَدَدْنَهُ أَسْفَلَ سَفِلِينَ )
إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ
فَلَهُمْ أَجْرُ غَيْرُ مَمْنُونٍ
فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ
أَلَيْسَ اللهُ بِأَحْكَمِ الْحَكِمِينَ }
سورد
ورة التين
1 - (میں) اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا
( اور ) بار بار رحم کرنے والا ہے ( پڑھتا ہوں )
2.میں انجیر کو اور زیتون کو شہادت کے طور پر پیش
کرتا ہوں.3.اور اسی طرح سینین کے پہاڑ کو.4.اور اس امن والے شہر (تلہ ) کو بھی.5.( یہ ساری شہادتیں ثابت کرتی ہیں کہ ) یقیناً ہم نے
انسان کو موزوں سے موزوں حالت میں پیدا کیا ہے.6.پھر ہم نے اس کو ادنی درجوں سے ( بھی ) بدتر
درجہ کی طرف لوٹا دیا.7.باستثناء ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور
جنہوں نے مناسب حال عمل کیے.سو اُن کے
لئے ایک نہ ختم ہونے والا نیک بدلہ ہو گا.8.پس اس ( حقیقت کے کھل جانے ) کے بعد کونسی
چیز تجھ کو جزا سزا کے معاملے میں جھٹلاتی ہے.9.کیا (اب بھی کوئی خیال کر سکتا ہے کہ ) اللہ
سب حاکموں سے بڑا حا کم نہیں؟
819
Page 828
حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں:
عربی میں آدمی کو انسان کہتے ہیں یعنی جس میں دو انس ہیں ایک انس خدا کی اور ایک
انس بنی نوع کی.خدا نے چاہا ہے کہ انسان خدا کے اخلاق پر چلے.جیسے وہ ہر ایک عیب اور بدی سے
پاک ہے یہ بھی پاک ہو.جیسے اس میں عدل ، انصاف اور علم کی صفت ہے وہی اس میں ہو
اس لئے اس خلق کو احسنِ تقویم کہا ہے.لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ جو
انسان خدائی اخلاق اختیار کرتے ہیں وہ اس آیت سے مراد ہیں اور اگر کفر کرے تو پھر
أسفل السافلین اس کی جگہ ہے.انسان اگر اللہ تعالیٰ کے لئے اپنی زندگی وقف نہ کرے اور اس کی مخلوق کے لئے نفع رساں نہ
ہو تو یہ ایک بریکار اور نکمی ہستی ہو جاتی ہے.بھیڑ بکری بھی پھر اس سے اچھی ہے جو انسان کے
کام تو آتی ہے لیکن یہ جب اشرف المخلوقات ہو کر اپنی نوع انسان کے کام نہیں آتا تو پھر بدترین
مخلوق ہو جاتا ہے.اسی کی طرف اشارہ کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ
في أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَهُ أَسْفَلَ سَفِلِينَ میں گرایا جاتا ہے.پس یہ سچی بات ہے کہ اگر
انسان میں یہ نہیں ہے کہ وہ خدا کے اوامر کی اطاعت کرے اور مخلوق کو نفع پہنچاوے تو وہ
جانوروں سے بھی گیا گزرا ہے اور بدترین مخلوق ہے.حضرت خلیفہ المسیح الثانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
(ماخوذ از تفسیر حضرت مسیح موعود علیہ السلام)
ما سورۃ انشراح میں بتایا گیا تھا کہ محمد رسول اللہ الا ایم کا انجام اچھا ہوگا کیونکہ نیک انجام
کے لئے جن امور کی ضرورت ہوتی ہے وہ آپ کو حاصل ہیں.اب اس سورۃ میں یہ بتایا گیا ہے
820
Page 829
کہ پہلی اقوام کی شہادت اس امر کی تائید میں موجود ہے.سورۃ الانشراح میں عقلی دلیل دی گئی تھی.اب اس سورۃ میں نقلی دلیل دی گئی ہے اور بتایا
گیا ہے کہ ایسے ہی حالات میں اللہ تعالیٰ نے بعض قوموں کو بھی ترقی دی ہے اس سے تم نتیجہ
نکال سکتے ہو کہ جس طرح آدم اور نوع اور موسیٰ کے وقت میں ہوا کہ باوجود مخالف حالات کے
محض روحانی سامانوں سے ان کو فتح حاصل ہوئی اب بھی ایسا ہی ہوگا.رض
حضرت خلیفہ المسیح الاول لکھتے ہیں کہ ان کی قسم اس لئے کھائی یعنی تین اور زیتون کی کہ
علاوہ غذا کے دوا کے طور پر بھی یہ استعمال ہوتی ہیں.کبھی طبیب تین تجویز کرتا ہے کبھی
زیتون.مطلب یہ کہ ایک زمانہ میں خدا تعالیٰ نے طور سینین کا نسخہ استعمال کیا اور اس
زمانہ میں بلد الامین کا نسخہ اس نے تجویز کر دیا.گویا...تین سے مراد بنی اسرائیل اور
زیتون سے مراد بلد الامین سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں.حضرت خلیفہ اول رضی اللہ عنہ کے معنی نہایت لطیف ہیں کہ ایک قوم کو تین
مشابہت دی گئی ہے اور دوسری کو زیتون سے.اور بتایا گیا ہے کہ ایک وقت ہم نے تین کا
نسخہ تجویز کیا تھا اور دوسرے وقت میں زیتون کا کیونکہ ہم کامل طبیب ہیں اور جیسی جیسی بیماری
ہوتی ہے ویسا ہی اس کا علاج کرتے ہیں.بلکہ میں کہتا ہوں کہ اس سے زیادہ اس جگہ یہ بھی
اشارہ کیا گیا ہے کہ تین مزے میں تو اچھی ہوتی ہے مگر وہ جلدی سڑ جاتی ہے.اس کے مقابل
میں زیتون علاوہ اس کے کہ پھل کا کام دیتا ہے اس کا روغن کثرت کے ساتھ استعمال کیا جاتا
ہے اور اچار میں بھی ڈالا جاتا ہے جو اس کو دیر تک قائم رکھتا ہے.گویات تین تو اپنی ذات میں
بھی قائم نہیں رہ سکتی اور زیتون کے ساتھ دوسری چیزیں بھی قائم رکھی جاتی ہیں اور ان دو مثالوں
کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے اس امر کی طرف اشارہ کیا ہے کہ موسوی تعلیم انجیر کی طرح سڑ جانے
والی تھی.اب ہم تمہیں وہ تعلیم دیں گے جو نہ صرف سڑنے اور خراب ہونے سے محفوظ رہے گی
بلکہ انسانی ذہنوں میں ایک ایسا نور پیدا کر دے گی کہ اس کے ذریعہ سے نئے سے نئے
821
Page 830
معارف اور نئے سے نئے علوم انہیں اس کتاب سے حاصل ہوتے رہیں گے.جیسے سورۃ نور
میں زیتون کے تیل کی تعریف کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ
تمسسه تار (النور (36).یہ تیل ایسا اعلیٰ درجہ کا ہے کہ خواہ آگ اس کے قریب نہ لائی جائے
تب بھی وہ خود بخود بھڑک اٹھتا ہے.ایسی اعلیٰ درجہ کی چیز کے ساتھ الہی کلام کومشابہ قراردینے
کے معنی یہی ہیں کہ وہ کلام جو اب دنیا میں نازل کیا جائے گا نئے سے نئے علوم اور معارف کو
دنیا میں قائم کرنے کا ایک ذریعہ ہوگا.اور جہالت اور معصیت کی تاریکیوں کو دور کر دے گا.ان
دونوں معنوں میں جو اوپر بیان کئے جاچکے ہیں ترتیب طبعی پائی جاتی ہے.ایک میں درجہ کے
لحاظ سے اور ایک میں زمانہ کے لحاظ سے.اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَد خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ ـ ان
مثالوں سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو نہایت معتدل القویٰ بنایا ہے.کیونکہ جب بھی
خدا تعالیٰ کے نبی آئے آخر دنیا ان کو مان گئی....اس لحاظ سے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي
أَحْسَنِ تَقویم کے یہ معنی ہوں گے کہ ان میں سے جس نبی کو بھی دیکھ لو تمہیں تسلیم کرنا پڑے گا
کہ آخر وہی فتح یاب ہوا.بیشک دنیا نے ان کی مخالفت کی.ان کو مٹانے کے لئے اس نے
مختلف قسم کی تدابیر اختیار کیں مگر آخر ان
کی تعلیم کو ماننے پر مجبور ہوگئی.اس سے یہ نتیجہ نکل آیا کہ
ہم نے انسان کو نہایت اعلیٰ درجہ کی تقویم میں پیدا کیا ہے.موسی" آئے تو ہم نے انہیں فتح
دی.عیسی علیہ السلام آئے تو ہم نے انہیں فتح دی.اب تم محمد رسول اللہ علیم کو نہیں مانتے
مگر ایک دن تمہیں اس کی تعلیم کے سامنے اپنے سر کو جھکانا پڑے گا اور اس طرح ثابت ہو جائے
گا کہ ہم نے انسان کو احسن تقویم میں پیدا کیا ہے.ا جب میں نے غور کیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ان آیات کا ایک نیا علم بخشا.اس کے لحاظ
سے یہاں نہ دو زمانوں کا ذکر ہے نہ تین کا بلکہ چار زمانوں کی خبر دی گئی ہے اور اس طرح ایک
نہایت ہی لطیف مضمون بیان کیا گیا ہے جو لَقَد خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ کے
822
Page 831
ساتھ گہرے طور پر تعلق رکھتا ہے.غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سورۃ سے پہلے کی چندسورتوں میں ہجرت کا ذکر چلا آتا
ہے.چنانچہ پہلے تو یہ بتایا گیا ہے کہ تمہیں ہجرت کرنی پڑے گی.پھر یہ بتایا گیا ہے کہ ہجرت
کس طرح ہوگی.اور پھر یہ بتایا گیا ہے کہ ہجرت کے بعد تمہیں کس طرح غلبہ حاصل ہوگا.کفار کیونکر مغلوب ہوں گے اور اسلام کو کس طرح شوکت اور عظمت حاصل ہوگی.پہلی مثال آدم کی ہے...یعنی جب شیطان نے آدم کو جنت میں سے نکالنے کا سامان کیا
تو آدم نے وَرَقُ الجنّة کو اپنے ساتھ لپٹا لیا اور اس طرح وہ ننگ جو ظاہر ہو گیا تھا اس کو
ڈھانک لیا....وَرَقُ الْجَنَّةِ تعبیر الرؤیا کے مطابق انجیر کے پتوں کو کہتے ہیں اور جیسا کہ انجیر
کے معنے صلحاء اور پاک طینت لوگوں کے ہیں.اسی طرح وَرَقُ الْجَنَّةِ کے معنے بھی جنتی نسل
کے ہیں اور جنتی نسل وہی ہوتی ہے جو صلحاء اور پاک لوگوں پر مشتمل ہو.اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالزَّيْتُونِ.دوسری مثال ہم زیتون کی دیتے ہیں.زیتون کی مثال نوح کا واقعہ ہے.نوع کو اس کی قوم نے سخت تنگ کیا اور آخر ایک عذاب
عظیم آیا جس کی وجہ سے نوع کی قوم تباہ ہوئی اور نوح کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا.نوح کو جس چیز نے یہ بشارت دی تھی کہ تیری ہجرت کامیاب ہوگئی ہے تو جیت گیا اور
تیرے دشمن ہمیشہ کے لئے مغلوب ہو گئے ہیں وہ زیتون کی پٹی تھی.اور آدم کو جس چیز نے یہ
بتایا کہ تو کامیاب ہو گیا ہے وہ انجیر کے پتے تھے.اللہ تعالیٰ انہی دو واقعات کی طرف اشارہ
کرتے ہوئے فرماتا ہے وَالتَّيْنِ وَالزَّيْتُونِ
پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم تین کا واقعہ بھی تمہارے سامنے پیش کرتے ہیں اور زیتون کا
واقعہ بھی تمہیں یاد دلاتے ہیں.دونوں جگہ ہجرت ہوئی مگر دونوں جگہ شیطان کو نا کامی ہوئی.آدم
نے ہجرت کی مگر آخر آدم ہی دشمن پر کامیاب ہوا.نوح نے ہجرت کی مگر آخر نوع ہی دشمن پر
کامیاب ہوا.نوح کے بعد وہ ملک جس میں آپ رہتے تھے پھر بسا نہیں بلکہ تباہ ہو گیا.823
Page 832
زیتون کے بعد طور سینین کی قسم کھائی گئی ہے یعنی اسے بھی شہادت کے طور پر پیش
کیا گیا ہے.سینین کیا چیز ہے؟ اس کے متعلق یاد رکھنا چاہیے کہ سینین ایک علاقہ
ہے جو دشت سینا کہلاتا ہے.قرآن کریم نے خور کا لفظ استعمال کیا ہے اور طور کے معنے پہاڑ کے بھی ہوتے ہیں.پس
طور سینین کے یہ معنی ہیں کہ سینا کا ایک پہاڑ.قرآن کریم سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس
نے طور کو اس پہاڑ کا نام قرار نہیں دیا بلکہ طور معنی پہاڑ استعمال کیا ہے.بعض مفسرین نے جو یہ سمجھا ہے کہ طور کسی پہاڑ کا نام ہے یہ درست نہیں.طور کے معنے
محض ایک پہاڑ کے ہیں اور انہیں معنوں میں یہ لفظ قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے.طور کے معنے پہاڑ کے ہیں اور طور کے لفظ سے اس پہاڑ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جس پر
حضرت موسیٰ سے کلام ہوا اور اس واقعہ کو چونکہ ہزاروں لوگوں نے بار بار بیان کیا آہستہ آہستہ
طور کا لفظ ہی بجائے پہاڑ کے ایک خاص پہاڑ کا علم یعنی مخصوص نام سمجھا جانے لگا.اللہ تعالیٰ موسیٰ" کی ہجرت کا واقعہ بطور مثال پیش کرتا ہے.قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے
کہ طور کا واقعہ ہجرت کے بعد ہوا ہے.غرض اللہ تعالیٰ آدم اور نوع کی مثالیں پیش کرنے کے بعد فرماتا ہے ہم تیسری مثال
تمہارے سامنے موسیٰ کی پیش کرتے ہیں.موسیٰ کو دشمن کے مظالم کی وجہ سے ہجرت کرنی پڑی
تھی اور وہ اپنی قوم کو ساتھ لے کر مصر سے باہر نکل آیا تھا.موسیٰ کے دشمنوں نے سمجھا ہوگا کہ چلو
چھٹی ہوئی ، ہمیں اس کے فتنہ سے نجات ملی مگر خدا نے اس ہجرت کو دشمنوں کی تباہی اور
بنی اسرائیل کی ترقی کا موجب بنادیا.اللہ تعالیٰ یہاں یہ مضمون بیان کر رہا ہے کہ محمد رسول اللہ علی ایم کو تمہاری تدبیروں سے کوئی
نقصان نہیں پہنچ سکتا.تین اور زیتون اور مطور سینین کے واقعات تمہارے سامنے ہیں.آدم کو شیطان نے دھوکا دیا تو تین نے اس کا ننگ ڈھانک لیا.نوح کے زمانہ میں طوفان آیا
824
Page 833
تو زیتون کی شاخ سے اس کو خوشخبری ملی.مصر سے موسیٰ کو بھا گنا پڑا تو طور سینین پر اس
کو پناہ مل گئی.چونکہ یہاں غلبہ اور ترقی کا مضمون ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے دشمن کی تکالیف
والے حصہ کو بیان نہیں کیا.ورنہ دراصل والثنین کے معنے ہیں شیطان کا آدم کو دھوکا دینا اور
تین سے اس کا کامیاب ہونا.وَالزِّيْتُون کے معنے ہیں نوح کے لئے عرصہ حیات کا تنگ کیا
جانا، طوفان آنا اور پھر زیتون سے نوح کو اپنی کامیابی کی بشارت ملنا.طور سینین کے معنے
ہیں مصر سے موسیٰ کا بھاگنا اور طور سینین پر اس کو اپنی کامیابیوں کی بشارت ملنا.اور ھذا
البلد الامین کے معنے ہیں مکہ سے محمد رسول اللہ علیم کا بھاگنا اور پھر آپ کا فاتح اور حکمران
ہونے کی حیثیت سے مکہ میں واپس آنا.مگر تکالیف اور ہجرت وغیرہ کا ذکر چونکہ مضمون سے
خود بخود نکل آتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر محض اشارہ کیا ہے.اصل ذکر غلبہ اور
کامیابی کا کیا ہے تا کہ دشمن اپنی عارضی کامیابی پر خوش نہ ہو اور وہ یہ خیال نہ کرے کہ اس نے
اللہ تعالیٰ کے انبیاء کو شکست دے دی ہے.اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهَذَا الْبَلَدِ الْآمین کہ ہم اس بلد الامین کو بھی
شہادت کے طور پر پیش کرتے ہیں.آمین کے معنے یا تو آئمن کے ہوتے ہیں اور یا مامون
کے ہوتے ہیں یعنی یا تو اس کے معنے ہیں کہ وہ بلد جو دنیا کو امن دیتا ہے اور یا پھر اس کے یہ
معنے ہیں کہ وہ بلد جس کو خدا نے مامون کر دیا ہے.میرے نزدیک بلد الامین کے دونوں معنے ہو سکتے ہیں.یہ بھی کہ وہ شہر جو امن دینے
والا ہے اور یہ بھی کہ وہ شہر جسے امن دیا گیا ہے.آمین کا لفظ جو اس آیت میں استعمال کیا گیا
ہے اس سے صاف پتہ لگتا ہے کہ جس وقت یہ سورۃ نازل ہوئی ہے اس وقت کے مکہ کی حالت کا
اس میں ذکر نہیں کیونکہ اس وقت تو جو کچھ کیفیت تھی اس کا ذکر اللہ تعالیٰ ان الفاظ میں کر چکا ہے
أنتَ حِلٌّ بِهذا البلد تجھے اس بلد میں حلال سمجھا جارہا ہے اور کوئی تکلیف نہیں جو تجھے نہ
پہنچائی جاتی ہو اور کوئی ظلم نہیں جو تجھ پر توڑا نہ جاتا ہو.ہر قسم کے تیروں کا نشانہ انہوں نے تجھ کو
825
Page 834
بنایا ہوا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ایک جائزہ فعل کا ارتکاب کر رہے ہیں.جس شہر میں محمدعلی یا لیلی
جیسے امن پسند انسان پر ظلم کیا جاتا تھا وہ تبلد الامین کس طرح کہلا سکتا تھا.پس بلدِ الْآمين
سے در حقیقت مگہ کی وہ حالت مراد ہے جو فتح مکہ کے بعد پیدا ہوئی جب ہر قسم کے مظالم کا
سلسلہ جاتارہاتھا اور مسلمانوں کو کفار پر غلبہ اور اقتدار حاصل ہو گیا تھا.ورنہ فتح مکہ سے پہلے وہ
بلد الامین کہاں تھا.نہ اس میں روحانی لحاظ سے امن تھا نہ جسمانی لحاظ سے....تین بھی
ہجرت کے بعد کا واقعہ ہے جب آدم شیطان پر کامیاب ہوئے.زیتون بھی ہجرت کے بعد کا
واقعہ ہے جب نوح طوفان سے بچے.طور سینین بھی ہجرت کے بعد کا واقعہ ہے جب موسیٰ
کو آئندہ ترقیات کی خوشخبری ملی.اسی طرح بلد الامین بھی ہجرت کے بعد کا واقعہ ہے جس کی
ابتدائی ملی زندگی میں پیشگوئی کردی گئی تھی اور بتایا گیا تھا کہ گو آج مسلمانوں پر مظالم
ڈھائے جاتے ہیں مگر ایک دن آنے والا ہے جب مکہ تمہارے لئے اور سب دنیا کے لئے
بلد الامین ہوگا.ہر قسم کے مظالم کا سلسلہ مٹ جائے گا اور محمد رسول اللہ علیم اور آپ کے
ساتھیوں کو امن حاصل ہو جائے گا.لقد خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ
حمد یقیناً ہم نے انسان کو موزوں سے موزوں حالت میں پیدا کیا ہے
تقویم کے معنی تعدیل کے ہیں یعنی کسی چیز کو صیح القولی بنانا اور ہرقسم کی کجی اور خرابی سے
اس کو محفوظ رکھنا.لقَد خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ کے مختلف معنے ہو سکتے ہیں.یہ بھی ہو سکتے ہیں
کہ ہم نے انسان کو بہترین وجود بنایا ہے.یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ ہم نے انسان کو بہترین
طاقتیں دے کر پیدا کیا ہے اور یہ معنے بھی ہو سکتے ہیں کہ انسان کو ہم نے بڑا صناع بنایا ہے.اس کے اندر تقویم کی طاقت رکھی ہے اور وہ اعلیٰ سے اعلیٰ روحانی اور جسمانی پیدائش کر سکتا ہے.یہ آیات بتاتی ہیں کہ آدم کا آنا، نوع کا آنا ہوسٹی کا آنا اور ان کا اپنی اصلاحی کوششوں
826
Page 835
میں کامیاب ہوجانا اور دنیا کا ایک نئے رنگ میں بدل جانا ثبوت ہے اس بات کا کہ خدا تعالیٰ نے
انسان کو احسن تقویم میں پیدا کیا ہے.یعنی انسانی پیدائش ایسے اصول پر ہوئی ہے کہ وہ اعتدال
کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پر پہنچ سکتا ہے...آدم ، نوع ، موسیٰ ، اور ان کے متبع اس امر کا ثبوت ہیں اور
محمد ام آئندہ اس بات کا ثبوت بننے والے ہیں کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ -
ثُمَّ رَدَدْتُهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ
پھر ہم نے اس کو ادنی درجوں سے ( بھی ) بددرجہ کی طرف لوٹا دیا
ردَدْنَاهُ میں ضمیر خدا تعالیٰ کی طرف پھرتی ہے اور یہ اس امر کے اظہار کے لئے کیا گیا
ہے کہ خدا تعالی بد کار کو بطور سزا اس کے مقام سے گرادیتا ہے.یہ مطلب نہیں کہ خدا تعالیٰ اس
سے بدی کرواتا ہے.یہ ایسا ہی ہے جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتا ہے کہ
آدم کو جنت میں سے ہم نے نکالا.اور یہ بھی فرمایا ہے کہ آدم کو جنت میں سے شیطان نے
نکالا.چنانچہ فرماتا ہے يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ
(الاعراف 28) یہ ظاہر ہے کہ آدم کو جنت میں سے شیطان کا نکالنا اور آدم کو جنت سے
اللہ تعالیٰ کا نکالنا ایک معنوں میں نہیں آسکتا.بہر حال تسلیم کرنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ کا نکالنا اور
رنگ رکھتا ہے اور شیطان کا نکالنا اور رنگ رکھتا ہے اور ان دونوں میں کوئی نہ کوئی فرق پایا جاتا
ہے.وہ فرق یہی ہے کہ شیطان چونکہ اس غلطی کا باعث بنا تھا جس کے نتیجہ میں آدم کو جنت
میں سے نکالا تھا.لیکن چونکہ نتیجہ خدا نے پیدا کیا تھا اس لئے دوسرے مقام پر یہ کہہ دیا گیا کہ
آدم کو خدا تعالیٰ نے جنت میں سے نکالا تھا.گویا شیطان کا نکالنا بلحاظ فعل بد کے ہے اور اللہ تعالیٰ کا
نکالنا بلحاظ اس سزا کے ہے جو اس فعل کے نتیجہ میں اللہ تعالی کی طرف سے ظاہر ہوئی.اسی طرح رددناه أسفل سافلین کے یہ معنی نہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کو بگاڑتا ہے.بلکہ
اس کے معنے یہ ہیں کہ جب انسان بگڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے سزا کے طور پر آسْفَلَ سَافِلِينَ
میں بھیج دیتا ہے...وہ ایک جرم کرتا ہے ہم اسے اس کی سزا دیتے ہیں.وہ پھر جرم کرتا ہے ہم
827
Page 836
اسے پھر سزا دیتے ہیں اور اس طرح اُسے ذلیل اور ادنیٰ حالت کی طرف لے جاتے ہیں.یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس آیت میں آسفل سافلین ضمیر کا حال واقع ہوا ہو.یعنی ذوالحال
فاعل نہ ہو بلکہ مفعول ذوالحال ہو.اس صورت میں آیت کے یہ معنی ہوں گے کہ پھر انسان کو ہم
نے اپنے دروازہ سے کو ٹا یا اس حال میں کہ وہ آسفل سافلین تھا.ان معنوں کے لحاظ سے وہ
اعتراض واقع نہیں ہو سکتا جو پہلے معنوں پر عائد ہوتا ہے اور ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ کا یہ
مفہوم ہو گا کہ ہم انسان کو اس کے مقام سے ہٹا دیتے ہیں ایسے حال میں کہ وہ أَسْفَلَ سَافِلِينَ
ہوتا ہے.یعنی جب وہ گنہگار ہو کر ہماری نظروں سے گر جاتا ہے تو ہم اسے اپنے دربار سے واپس
کر دیتے ہیں.اس آیت کے ایک معنی فردی لحاظ سے ہیں اور ایک معنی اجتماعی لحاظ سے.اجتماعی لحاظ
سے اس کے یہ معنے ہیں کہ ہدایت پہلے ہے اور ضلالت بعد میں آتی ہے.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ - ثُمَّ رَدَدْنَهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ پہلے ہم انسان کے
لئے اس کی ہدایت کے سامان مہیا کرتے ہیں بعد میں بگڑ کر وہ ضلالت اور گمراہی کی راہیں
اختیار کر لیتا ہے.فرد کے لحاظ سے اس کے یہ معنے ہیں کہ انسان کو ہم نے ہدایت دی اور اعلیٰ درجہ کی
طاقتیں نیکی میں ترقی کرنے کے لئے بخشیں.لیکن جب اس نے ان کا غلط استعمال کیا تو وہ
أَسْفَلَ سَافِلِین میں گر گیا.یعنی انسان کی دونوں حالتیں دوسری مخلوق سے بڑی ہیں.جب
نیکی کی طرف آتا ہے تو سب مخلوق سے بڑھ جاتا ہے اور جب بدی کی طرف گرتا ہے تو ساری
مخلوق سے گر جاتا ہے.انسان کو اللہ تعالیٰ نے اضداد کا مالک بنایا ہے.نیکی میں حصہ لیتا ہے
تو ساری مخلوق سے بڑھ جاتا ہے اور بدی میں حصہ لیتا ہے تو کٹوں اور سؤروں سے بھی گرجاتا
ہے.یا یوں کہو کہ وہ ترقی کرتا ہے تو فرشتوں سے بھی بڑھ جاتا ہے اور گرتا ہے تو شیطانوں سے
بھی نیچے چلا جاتا ہے.گو یالَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ میں بالقوه توی کا ذکر ہے
828
Page 837
اور ثُمَّ رَدَدْنَاة اور الَّا الَّذِينَ آمَنُوا میں بالظهور قوی کا ذکر ہے.یعنی بالقوہ تو سب کو اچھے قویٰ
ملے ہیں مگر جب ان کا ظہور ہوتا ہے تو دو طرح ہوتا ہے.یا تو انسان مومن بن جاتا ہے اور یا کافر
بن جاتا ہے.مومن بن کر اوپر کونکل جاتا ہے اور کافر بن کر نیچے کی طرف گر جاتا ہے.إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ
باستثناء ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے مناسب حال عمل کئے سو اُن کے لئے
ایک نہ ختم ہونے والا ( نیک ) بدلہ ہوگا.اس آیت میں اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کا استثنا کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو
ایمان لاتے اور اعمال صالحہ کی بجا آوری میں ہمیشہ مشغول رہتے ہیں ان کو ہم أَسْفَلَ سَافِلِين
میں نہیں لوٹاتے.کیونکہ وہ فطرت کو صحیح راستہ پر چلاتے اور اپنی قوتوں کا جائز اور برمحل استعمال
کرتے ہیں.یہاں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے احسن تقویم کے ذکر میں ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ
سافلین کو پہلے کیوں رکھا ہے.اور إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ کا ذکر پیچھے کیوں کیا
ہے؟ اور اس تقدیم و تاخیر میں کیا حکمت ہے؟
اس کا جواب یہ ہے کہ ایمان اور اعمال صالحہ چونکہ طبعی اور فطری قوی کے صحیح استعمال کا نام
ہے اور جو شخص احکام الہیہ پر ایمان لاتا ہے اور پھر ان کے مطابق اعمال صالحہ بھی بجالاتا ہے وہ
در حقیقت اس راستہ پر چلتا چلا جاتا ہے جو فطرت کا راستہ ہے اور اس کے نتیجہ میں اسے مذہب
جیسی نعمت حاصل ہوتی ہے.اور وہ ایمان اور اعمال کی برکات سے متمتع ہوتا ہے.اس لئے
ضروری تھا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا الّا کہہ کر علیحدہ ذکر فرماتا.اور اس طرح اسفل
سَافِلِین میں جانے والوں اور فطری استعدادوں سے صحیح طور پر کام لینے والوں میں ایک
ما بہ الامتیا ز قائم ہو جاتا.رہا یہ سوال کہ آسفل سافلین میں گرنے والوں کا پہلے کیوں ذکر کیا ہے؟ اس کا جواب یہ
829
Page 838
ہے کہ چونکہ وہ لوگ اپنی پیدائش کے مقصد کو فراموش کرنے والے تھے اس لئے ضروری تھا
کہ جب یہ ذکر کیا گیا تھا کہ ہم نے انسان کو معتدل القویٰ پیدا کیا ہے اور اس کی فطرت میں
نیکی اور بھلائی کی قوتیں رکھ دی ہیں وہاں ساتھ ہی اس شبہ کا ازالہ بھی کر دیا جاتا کہ اگر ایسا ہے تو
بعض لوگ بدکیوں ہوتے ہیں.چنانچہ اس کا جواب یہ دیا ہے کہ گوہم نے انسان کو اسی مقصد
کے لئے پیدا کیا ہے مگر پھر بھی بعض لوگ چونکہ اپنی فطرت کو مسخ کر دیتے اور اللہ تعالیٰ کی عطا
کردہ قوتوں کا ناجائز استعمال کرتے ہیں وہ مقام رفعت سے گر کر ذلت اور ادبار کے گڑھے
میں جا پڑتے ہیں اور انسانیت کے لئے ان کا وجود ننگ و عار کا باعث بن جاتا ہے.یہ ان کا اپنا
قصور ہوتا ہے خدا تعالیٰ اس کا ذمہ دار نہیں.اس کے بعد إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ
فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ کہہ کر ایمان لانے والوں اور عمل صالحہ کی بجا آوری میں مشغول رہنے
والوں کا استثنی کردیا اور بتادیا کہ جولوگ احسن تقویم پر قائم رہتے اور اس رستہ پر چلتے چلے جاتے
ہیں جو فطرت صحیحہ کا ہے اللہ تعالیٰ ان کو دولتِ ایمان سے مشرف کر دیتا ہے.اور انہیں اس
بات کی بھی توفیق عطا فرما دیتا ہے کہ وہ اعمال صالحہ بجالائیں.گویا ایمان اور عمل صالح کا راستہ
فطرت صحیحہ کی لائن کے ساتھ ساتھ چلتا ہے.جو لوگ فطرت کو بگاڑ لیتے ہیں اور اپنے قویٰ
استعداد یہ سے صحیح رنگ میں کام نہیں لیتے وہ تو اسفل سافلین میں جا گرتے ہیں لیکن وہ لوگ جو
فطری اور طبعی راستہ پر چلتے چلے جاتے ہیں، اپنی قوتوں کو برمحل استعمال کرتے ہیں اور فطرت کو
مسخ کرنے کی کوشش نہیں کرتے ان کو ایمان بھی عطا کیا جاتا ہے اور ان میں اعمال صالحہ
بھی پیدا ہو جاتے ہیں.ایسے لوگ آسفل سافلین میں نہیں لوٹائے جاتے بلکہ اللہ تعالیٰ کی
طرف سے ان کو غیر ممنون یعنی جزائے غیر مقطوع حاصل ہوتی ہے.اور اس طرح صحیح علم
اور اس کے صحیح استعمال کی وجہ سے وہ ہمیشہ کے لئے اعلیٰ انعامات کے مستحق ہو جاتے ہیں.امَنُوا میں صحیح علم کی طرف اشارہ ہے یعنی وہ علم جو مناسب حال ہو اور عملوا الصلحت میں اس
830
Page 839
م کے صحیح استعمال یعنی صحیح عمل کی طرف اشارہ ہے اور یہی دو چیزیں ہیں جو روحانی ترقی میں کام
آیا کرتی ہیں.فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ
پس اس ( حقیقت کے کھل جانے) کے بعد کونسی چیز تجھ کو جزا وسزا کے معاملے میں
جھٹلاتی ہے.یعنی یہ تین مثالیں جو او پر پیش کی جاچکی ہیں کہ آدم آئے شیطان نے ان کا مقابلہ کیا اور
اس نے سمجھا کہ میں آدم کو شکست دینے میں کامیاب ہو جاؤں گا مگر آخر شیطان نے ہی شکست
کھائی اور آدم کامیاب و با مراد ہوا.پھر نوع آئے ، دشمن نے ان کا مقابلہ کیا.ان کو نا کام
کرنے کے لئے اس نے پورا زور لگایا اور سمجھا کہ میں نوح کو شکست دینے میں کامیاب ہو
جاؤں گا مگر آ خر نوع ہی کامیاب ہوئے اور ان کا دشمن ناکامی کی حالت میں تباہ ہو گیا.اس کے
بعد موسیٰ علیہ السلام آئے ان کے مقابل میں بھی دشمن اپنے لشکر سمیت اٹھا اور اس نے موسی کو
نا کام کرنے کے لئے پورا زور لگایا مگر آخر موسی ہی کامیاب ہوئے اور دشمن ناکام ہوا.ان تین
مثالوں کے بعد تیرے دشمن کس دلیل کی بنا پر تجھے جھٹلا سکتے ہیں اور کونسی بات ہے جو وہ تیرے
خلاف پیش کر سکتے ہیں.وہ کہیں گے کہ تو کمز ور اور نا تواں ہے تو ہمارے مقابلہ میں کامیاب
نہیں ہوسکتا مگر کیا وہ نہیں دیکھتے کہ آدم بھی کمز ور تھا.نوح بھی کمز ور تھا.موسیٰ بھی کمزور تھا.اور
ان کے متعلق بھی یہی سمجھا جاتا تھا کہ وہ کامیاب نہیں ہوں گے.پھر اگر وہ اپنی کمزوری کے
باوجود کامیاب ہو گئے تو تو کمزور ہونے کے باوجود ان پر کیوں غالب نہیں آ سکتا.غرض فرماتا ہے فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ اے محمد ملا لیں ان مثالوں کے بعد یہ لوگ
تیرے انعام پانے اور اپنے بلاک ہونے میں دین حقہ کی بنا پر کس طرح شک کر سکتے
ہیں.ان مثالوں کے بعد کونسی دلیل ہے جو ان کو شبہ میں مبتلا رکھ سکتی ہے یا کون سا انسان ہے
جودین کی بنا پر تیری تکذیب کر سکتا ہے.831
Page 840
دوسرے معنے اس آیت کے یہ ہیں کہ ان پہلی تین مثالوں کی موجودگی میں خدا تعالیٰ کی
طرف سے آنے والے دین یعنی الہامی دین کا یہ لوگ کس طرح انکار کر سکتے ہیں.ان معنوں کے
رُو سے یہاں دین کے معنے جزا سزا کے نہیں ہوں گے بلکہ دین کے معنے شریعت کے ہوں گے
اور آیت کا یہ مفہوم ہوگا کہ ان دلائل کے بعد دین کے معاملہ میں کون شخص تیرا انکار کر سکتا ہے.تیسرے معنے اس آیت کے یہ ہیں کہ ان دلائل کے بعد آیا کوئی بھی مذہبی دلیل تیرے
خلاف پیش کی جاسکتی ہے.یقیناً اگر وہ غور کریں تو انہیں تیری تکذیب کے لئے کسی مذہبی دلیل
کا سہارا نہیں مل سکتا کیونکہ آدم ، نوع ، اور ابراہیم کی سنت تجھ سے پہلے موجود ہے.جس معیار پر
ان نبیوں کو پر کھا گیا اگر انہی دلائل پر تجھے پر کھا جائے تو تیری صداقت یقینا ثابت ہوگی.چوتھے معنے اس آیت کے یہ ہیں کہ کیا اس کے بعد کوئی شخص بھی یہ سمجھ سکتا ہے کہ میں
تدبیر کر کے تجھے جھوٹا ثابت کر دوں گا.دین کے ایک معنے تدبیر کے بھی ہوتے ہیں.پس
آیت کا یہ مطلب ہوا کہ کیا اتنے بڑے نشانوں کے باوجود ہم نے تیری صداقت میں ظاہر کئے
ہیں کوئی شخص یہ خیال بھی کر سکتا ہے کہ تو ہار جائے گا اور دشمن جیت جائے گا.پانچویں معنے اس آیت کے یہ ہیں کہ تقویٰ قائم رکھتے ہوئے کون شخص تیری مخالفت
کرے گا.کیونکہ دین کے ایک معنے ورع یعنی تقویٰ اور روحانیت کے بھی ہیں.اور مطلب یہ
ہے کہ خدا تعالیٰ کی خشیت اور اس کی سزا کا خوف اپنے دل میں رکھتے ہوئے اور تقویٰ اور
روحانیت کی راہوں پر چلتے ہوئے کوئی شخص تیری مخالفت نہیں کرسکتا.صرف وہی گندے اور
نا پاک طبع دشمن تیری مخالفت میں کھڑے ہو سکتے ہیں جن کے اندر تقویٰ کا ایک شائبہ بھی نہ ہو اور
جو نیکی اور روحانیت کے مقام سے ایسے ہی دُور ہوں جیسے مشرق سے مغرب دُور ہوتا ہے.چھٹے معنے یہ ہیں کہ اب اس کے بعد کون اکراہ کے ساتھ تیری تکذیب کرے گا یعنی
سابق دشمنوں کا انجام دیکھ کر پھر کون بدنیت ہوگا جو جبر کے ہتھیار سے تیرا مقابلہ کرنا چاہیے اور یہ
خیال کرے کہ میں مار پیٹ کر سیدھا کرلوں گا پہلے نبیوں کو بھی مارنے پیٹنے کی دھمکیاں دی گئیں
تھیں مگر کیا ان کے دشمن کامیاب ہو گئے دشمن کا اکراہ اس کے کسی کام نہ آیا اور اس کا جبر
832
Page 841
خدا تعالیٰ کے دین کی اشاعت کو روک نہ سکا.ان مثالوں کے بعد اب ان لوگوں کے دلوں میں
یہ خیال کس طرح آ سکتا ہے کہ ہم نے اگر جبر و تشدد سے کام لیا تو ہم کامیاب ہو جائیں گے.اللہ تعالیٰ کا دین بہر حال پھیل کر رہے گا.اسلام دنیا پر غالب آئے گا اور کسی قسم کی روک اس کی
ترقی میں حائل نہیں ہو سکے گی.اليس الله يا حكم الحكمين
کیا ( اب بھی کوئی خیال کر سکتا ہے کہ ) اللہ سب حاکموں سے بڑا حا کم نہیں
فرماتا ہے کیا ان سارے دلائل اور نصیحتوں کو سن کر بھی ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی
کہ اللہ تعالیٰ سے بہتر فیصلہ کرنے والا اور کوئی نہیں.جس بات کا وہ فیصلہ کر دے اس کو دنیا کی
کوئی بڑی سے بڑی طاقت بھی روک نہیں سکتی.اس نے فیصلہ کیا کہ آدم کامیاب ہوسو وہ
کامیاب ہو گیا.اس نے فیصلہ کیا کہ نوح کو اپنے دشمنوں پر غلبہ حاصل ہوسواسے غلبہ حاصل ہو
گیا.اس نے فیصلہ کیا کہ موسیٰ کو ترقی حاصل ہوسواسے ترقی حاصل ہوگئی.اب اس نے فیصلہ
کیا ہے کہ محمد رسول الله علی ایم کو ترقی دے سوا سے ترقی حاصل ہو جائے گی.اور مکہ والوں کی
ہوائی باتیں اللہ تعالیٰ کے فیصلہ کے مقابلہ میں ٹھہر نہیں سکیں گی اور دنیا دیکھ لے گی کہ آخری
فیصلہ اللہ تعالی کے ہی ہاتھ میں ہے.(ماخوذ از تفسیر کبیرزیر سورة التين )
833
Page 843
بِسْمِ
اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا
وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَان
وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَان
يَوْمَبِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَانُ
بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَان
يَوْمَذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا
لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْن
سورة الزلزال
1 - (میں) اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا
( اور ) بار بار رحم کرنے والا ہے ( پڑھتا ہوں )
2.جب زمین کو پوری طرح بلا دیا جائے گا.3.اور زمین اپنے بوجھ کو نکال کر پھینک ) دے گی.4.اور انسان کہہ اٹھے گا کہ اسے کیا ہو گیا ہے.5.اس دن وہ اپنی ( ساری ہی پوشیدہ ) خبریں بیان
کردے گی.6.اس لئے کہ تیرے رب نے اس ( زمین ) کے
حق میں وحی کر چھوڑی ہے.7.اس دن لوگ مختلف گروہوں کی صورت میں جمع
ہوں گے تا کہ انہیں ان کے اعمال کی حقیقت
دکھائی جائے.فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ
8.پھر جس نے ایک ذرہ کے برابر ( بھی ) نیکی کی
ہوگی وہ اس ( کے نتیجہ ) کو دیکھ لے گا.وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهُ أَ 9.اور جس نے ایک ذرہ کے برابر بھی بدی کی
ہوگی وہ اس (کے نتیجہ ) کو دیکھ لے گا.835
Page 844
حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں:
إِذَا زُلْزِلَتِ کے لفظ سے اِس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جب تم یہ نشانیاں دیکھو تو
سمجھ لو کہ وہ لیلۃ القدر اپنے تمام تر زور کے ساتھ پھر ظاہر ہوئی ہے اور کوئی ربانی مصلح خدائے
تعالیٰ کی طرف سے مع ہدایت پھیلانے والے فرشتوں کے نازل ہو گیا ہے جیسا کہ فرماتا ہے
إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَاَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ
تُحدِثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ فَمَنْ
يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَر اترة.یعنی اُن دنوں کا جب آخری
زمانہ میں خدائے تعالیٰ کی طرف سے کوئی عظیم الشان مصلح آئے گا اور فرشتے نازل ہوں گے یہ
نشان ہے کہ زمین جہاں تک اُس کا بلا نا ممکن ہے بلائی جائے گی.یعنی طبیعتوں اور دلوں اور
دماغوں کو غایت درجہ پر جنبش دی جائے گی اور خیالات عقلی اور فکری اور سبھی اور بہیمی پورے
پورے جوش کے ساتھ حرکت میں آجائیں گے اور زمین اپنے تمام بوجھوں کو باہر نکال دے.گی
یعنی انسانوں کے دل اپنی تمام استعدادات مخفیہ کو بمنصہ ظہور لائیں گے اور جو کچھ ان کے
اندر علوم وفنون کا ذخیرہ ہے یا جو کچھ عمدہ عمدہ دلی و دماغی طاقتیں ولیاقتیں ان میں مخفی ہیں سب کی
سب ظاہر ہوجائیں گی.اور انسانی قوتوں کا آخری نچوڑ نکل آئے گا.اور جو جو ملکات انسان کے
اندر ہیں یا جو جو جذبات اس کی فطرت میں مؤدَع ہیں وہ تمام مکمن قوت سے حیر فعل میں آجائیں
گے.اور انسانی حواس کی ہر یک نوع کی تیزیاں اور بشری عقل کی ہر قسم کی باریک بینیاں
نمودار ہو جائیں گی.اور تمام دفائن و خزائن علوم مخفیہ وفنون مستورہ کے جو چھپے ہوئے چلے آتے
تھے اُن سب پر انسان فتحیاب ہو جائے گا.اور اپنی فکری اور عقلی تدبیروں کو ہر یک باب میں
انتہا تک پہنچا دے گا.اور انسان کی تمام قوتیں جو نشا انسانی میں مختمر میں صد با طرح کی تحریکوں
836
Page 845
کی وجہ سے حرکت میں آجائیں گی اور فرشتے جو اس لیلۃ القدر میں مرد مصلح کے ساتھ آسمان
سے اُترے ہوں گے ہر ایک شخص پر اس کی استعداد کے موافق خارق عادت اثر ڈالیں گے.یعنی نیک لوگ اپنے نیک خیال میں ترقی کریں گے اور جن کی نگاہیں دنیا تک محدود ہیں وہ اُن
فرشتوں کی تحریک سے دنیوی عقلوں اور معاشرت کی تدبیروں میں وہ ید بیضا دکھلائیں گے کہ
ایک مرد عارف متحیر ہو کر اپنے دل میں کہے گا کہ یہ عقلی اور فکری طاقتیں ان لوگوں کو کہاں سے
ملیں؟ تب اُس روز هر یک استعداد انسانی بزبان حال باتیں کرے گی کہ یہ اعلیٰ درجہ کی طاقتیں
میری طرف سے نہیں بلکہ خدائے تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک وحی ہے جو ہر یک استعداد پر
بحسب اُس کی حالت کے اُتر رہی ہے.یعنی صاف نظر آئے گا کہ جو کچھ انسانوں کے دل و
دماغ کام کر رہے ہیں.یہ ان کی طرف سے نہیں بلکہ ایک غیبی تحریک ہے کہ اُن سے یہ کام کرا
رہی ہے.سو اس دن ہر ایک قسم کی قوتیں جوش میں دکھائی دیں گی دنیا پرستوں کی قوتیں
فرشتوں کی تحریک سے جوش میں آکر اگرچہ بباعث نقصان استعداد کے سچائی کی طرف رُخ
نہیں کریں گی لیکن ایک قسم کا اُبال ان میں پیدا ہو کر اور انجماد اور افسردگی دور ہو کر اپنی
معاشرت کے طریقوں میں عجیب قسم کی تدبیریں اور صنعتیں اور گلیں ایجاد کرلیں گے اور نیکوں
کی قوتوں میں خارق عادت طور پر الہامات اور مکاشفات کا چشمہ صاف صاف طور پر بہتا نظر
آئے گا اور یہ بات شاذ و نادر ہوگی کہ مومن کی خواب جھوٹی نکلے تب انسانی قوی کے ظہور و بروز کا
دائرہ پورا ہو جائے گا اور جو کچھ انسان کے نوع میں پوشیدہ طور پر ودیعت رکھا گیا تھا وہ سب
خارج میں جلوہ گر ہو جائے گا.تب خدائے تعالیٰ کے فرشتے ان تمام راستبازوں کو جو زمین کی
چاروں طرفوں میں پوشیدہ طور پر زندگی بسر کرتے تھے ایک گروہ کی طرح اکٹھا کردیں گے اور
دنیا پرستوں کا بھی کھلا کھلا ایک گروہ نظر آئے گا تا ہر ایک گروہ اپنی کوششوں کے ثمرات کو
دیکھ لیو یں تب آخر ہو جائے گی.یہ آخری لیلة القدر کا نشان ہے جس کی بنا ابھی سے ڈالی گئی
ہے جس کی تکمیل کے لئے سب سے پہلے خدائے تعالیٰ نے اس عاجز کو بھیجا ہے اور مجھے مخاطب
837
Page 846
کر کے فرمایا کہ اَنْتَ اَشَدُّ مُنَاسَبَةً بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَاشْبَهُ النَّاسِ بِهِ خُلْقًا وَ خَلْقًا وَ
زمانًا مگر یہ تاثیرات اس لیلۃ القدر کی اب بعد اس کے کم نہیں ہوں گی بلکہ بالا تصال کام
کرتی رہیں گی جب تک وہ سب کچھ پورا نہ ہو لے جو خدائے تعالیٰ آسمان پر مقرر کر
چکا ہے.اور حضرت عیسی علیہ السلام نے اپنے اترنے کے لئے جو زمانہ انجیل میں بیان فرمایا
ہے یعنی یہ کہ وہ حضرت نوح کے زمانہ کی طرح امن اور آرام کا زمانہ ہوگا در حقیقت اسی مضمون پر
سورۃ الزلزال جس کی تفسیر ابھی کی گئی ہے دلالت التزامی کے طور پر شہادت دے رہی ہے.کیونکہ علوم وفنون کے پھیلنے اور انسانی عقول کی ترقیات کا زمانہ در حقیقت ایسا ہی چاہئے جس میں
غایت درجہ کا امن و آرام ہو کیونکہ لڑائیوں اور فسادوں اور خوف جان اور خلاف امن زمانہ میں
ہر گز ممکن نہیں کہ لوگ عقلی و عملی امور میں ترقیات کر سکیں.یہ باتیں تو کامل طور پر تبھی سوجھتی ہیں
کہ جب کامل طور پر امن حاصل ہو.ہمارے علماء نے جو ظاہری طور پر اس سورۃ الزلزال کی ی تفسیر کی ہے کہ در حقیقت زمین
کو آخری دنوں میں سخت زلزلہ آئے گا اور وہ ایسا زلزلہ ہوگا کہ تمام زمین اُس سے زیروز بر ہو
جائے گی اور جوزمین کے اندر چیزیں ہیں وہ سب باہر آجائیں گی اور انسان یعنی کا فرلوگ زمین
کو پوچھیں گے کہ تجھے کیا ہوا ؟ تب اُس روز زمین باتیں کرے گی اور اپنا حال بتائے گی.یہ
سراسر غلط تفسیر ہے کہ جو قرآن شریف کے سیاق وسباق سے مخالف ہے.اگر قرآن شریف کے اس مقام پر بنظر غور تدبر کرو تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ دونوں سورتیں
یعنی سورۃ البینہ اور سورۃ الزلزال ، سورۃ لیلۃ القدر کے متعلق ہیں اور آخری زمانہ تک اس کا گل
حال بتلا رہی ہیں.ماسوا اس کے ہر یک عقل سلیم سوچ سکتی ہے کہ ایسے بڑے زلزلہ کے وقت
میں کہ جب ساری زمین تہ و بالا ہو جائے گی ایسے کافر کہاں زندہ رہیں گے جو زمین سے اُس کے
حالات استفسار کریں گے.کیا ممکن ہے کہ زمین تو ساری زیروز بر ہو جائے یہاں تک کہ اوپر کا
طبقہ اندر اور اندر کا طبقہ باہر آ جائے اور پھر لوگ زندہ بچ رہیں؟ بلکہ اس جگہ زمین سے مراد زمین
838
Page 847
کے رہنے والے ہیں.اور یہ عام محاورہ قرآن شریف کا ہے کہ زمین کے لفظ سے انسانوں کے
دل اور ان کے باطنی قومی مراد ہوتے ہیں جیسا کہ اللہ جل شانہ ایک جگہ فرماتا ہے اِعْلَمُوا أَنَّ
الله يُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا (الحدید 18 ).اور جیسا کہ فرماتا ہے الْبَلدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ
نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُكَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا (الاعراف 59).ایسا ہی قرآن شریف
میں بیسیوں نظیریں موجود ہیں جو پڑھنے والوں پر پوشیدہ نہیں.ماسوا اس کے روحانی واعظوں کا
ظاہر ہونا اور ان کے ساتھ فرشتوں کا آنا ایک روحانی قیامت کا نمونہ ہوتا ہے جس سے مردوں
میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے اور جو قبروں کے اندر ہیں وہ باہر آجاتے ہیں اور نیک اور بدلوگ
اپنی سزا جزا پالیتے ہیں.سواگر سورۃ الزلزال کو قیامت کے آثار میں سے قرار دیا جائے تو اس
میں بھی کچھ شک نہیں کہ ایسا وقت روحانی طور پر ایک قسم کی قیامت ہی ہوتی ہے.خدائے
تعالی کے تائید یافتہ بندے قیامت کا ہی رُوپ بن کر آتے ہیں اور انہیں کا وجود قیامت کے نام
سے موسوم ہو سکتا ہے جن کے آنے سے روحانی مردے زندہ ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور نیز
اس میں بھی کچھ شک نہیں کہ جب ایسا زمانہ آجائے گا کہ تمام انسانی طاقتیں اپنے کمالات کو
ظاہر کر دکھائیں گی اور جس حد تک بشری عقول اور افکار کا پرواز ممکن ہے اس حد تک وہ پہنچ
جائیں گی اور جن مخفی حقیقتوں کو ابتدا سے ظاہر کرنا مقدر ہے وہ سب ظاہر ہو جائیں گی تب اس
عالم کا دائرہ پورا ہو کر ایک دفعہ اس کی صف لپیٹ دی جائے گی.كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى
وَجْهُ رَبَّكَ ذُو الْجَللِ وَالْإِكْرَامِ.(الرحمن:27-28)
(ازالہ اوہام، روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 161 تا169)
اس وقت زمین پر سخت زلزلہ آئے گا اور زمین اپنے تمام خزائن اور دفائن باہر نکال دے
گی.یعنی علوم ارضیہ کی خوب ترقی ہوگی مگر آسمانی علوم کی نہیں.(ازالہ اوہام ، روحانی خزائن جلد 3 صفحه 469)
وہ آیات جن میں اول ارضی تاریکی زور کے ساتھ پھیلنے کی خبر دی گئی ہے اور پھر آسمانی
روشنی کے نازل ہونے کی علامتیں بتلائی گئی ہیں وہ یہ ہیں.یہ سورت إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ
839
Page 848
زِلْزَالَهَا وَاخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَيْثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ
رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا.یعنی آخری زمانہ اس وقت آئے گا کہ جس وقت زمین ایک ہولناک جنبش
کے ساتھ جو اس کی مقدار کے مناسب حال ہے بلائی جائے گی یعنی اہل الارض میں ایک تغیر
عظیم آئے گا اور نفس اور دنیا پرستی کی طرف لوگ جھک جائیں گے اور پھر فرمایا کہ زمین اپنے
تمام بوجھ نکال ڈالے گی یعنی زمینی علوم اور زمینی مکر اور زمینی چالا کیاں اور زمینی کمالات جو کچھ
انسان کی فطرت میں مودع ہیں سب کی سب ظہور میں آجائیں گی اور نیز زمین جس پر انسان
رہتے ہیں اپنے تمام خواص ظاہر کر دے گی اور علم طبعی اور فلاحت کے ذریعہ سے بہت سی
خاصیتیں اس کی معلوم ہو جائیں گی اور کا نیں نمودار ہوں گی اور کاشتکاری کی کثرت ہو جائے گی.غرض زمین زرخیز ہو جائے گی اور انواع اقسام کی کلیں ایجاد ہوں گی یہاں تک کہ انسان کہے گا
کہ یہ کیا ماجرا ہے اور یہ نئے نئے علوم اور نئے نئے فنون اور نئی نئی صنعتیں کیوں کر ظہور میں آتی
جاتی ہیں تب زمین یعنی انسانوں کے دل زبان حال سے اپنے قصے سنائیں گے کہ یہ نئی باتیں جو
ظہور میں آرہی ہیں یہ ہماری طرف سے نہیں یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک قسم کی وحی ہے کیونکہ
ممکن نہیں کہ انسان اپنی کوششوں سے اس قدر علوم عجیبہ پیدا کر سکے.اور یادر ہے کہ ان آیات کے ساتھ جو قرآن کریم میں بعض دوسری آیات جو آخرت
کے متعلق ہیں شامل کی گئی ہیں وہ در حقیقت اسی سنت اللہ کے موافق شامل فرمائی گئی ہیں جس کا
ذکر پہلے ہو چکا ہے ورنہ اس میں کچھ شک نہیں کہ حقیقی اور مقدم معنی ان آیات کے یہی ہیں جو ہم
نے بیان کئے اور اُس پر قرینہ جو نہایت قوی اور فیصلہ کرنے والا ہے یہ ہے کہ اگر ان آیات
کے حسب ظاہر معنے کئے جائیں تو ایک فساد عظیم لازم آتا ہے.یعنی اگر ہم اس طور سے معنے
کریں کہ کسی وقت با وجود قائم رہنے اس آبادی کے جو دنیا میں موجود ہے.ایسے سخت زلزلے
زمین پر آئیں گے جو تمام زمین کے اوپر کا طبقہ نیچے اور نیچے کا اوپر ہو جائے گا.تو یہ بالکل
غیر ممکن اور ممتنعات میں سے ہے.آیت موصوفہ میں صاف لکھا ہے کہ انسان کہیں گے کہ
840
Page 849
زمین کو کیا ہو گیا.پھر ا گر حقیقتا یہی بات سچ ہے کہ زمین نہایت شد ید زلزلوں کے ساتھ زیروز بر
ہو جائے گی تو انسان کہاں ہوگا جو زمین سے سوال کرے گا.وہ تو پہلے ہی زلزلہ کے ساتھ زاویہ
عدم میں مخفی ہو جائے گا.علوم حسیہ کا تو کسی طرح سے انکار نہیں ہوسکتا.پس ایسے معنی کرنا جو
ببداہت باطل اور قرائن موجودہ کے مخالف ہوں گویا اسلام سے ہنسی کرانا اور مخالفین کو اعتراض
کے لئے موقعہ دینا ہے.پس واقعی اور حقیقی معنی یہی ہیں جو ابھی ہم نے بیان کئے.اب ظاہر ہے کہ یہ تغیرات اور فتن اور زلازل ہمارے زمانہ میں قوم نصاری سے ہی ظہور میں
آئے ہیں جن کی نظیر دنیا میں کبھی نہیں پائی گئی.پس یہ ایک دوسری دلیل اس بات پر ہے کہ
یہی قوم وہ آخری قوم ہے جس کے ہاتھ سے طرح طرح کے فتنوں کا پھیلنا مقدر تھا جس نے دنیا
میں طرح طرح کے ساحرانہ کام دکھلائے اور جیسا کہ لکھا ہے کہ دنبال نبوت کا دعویٰ کرے گا اور
نیز خدائی کا دعوی بھی اس سے ظہور میں آئے گا.وہ دونوں باتیں اس قوم سے ظہور میں آگئیں.نبوت کا دعویٰ اِس طرح پر کہ اس قوم کے پادریوں نے نبیوں کی کتابوں میں بڑی گستاخی سے
دخل بیجا کیا اور ایسی بیباکانہ مداخلت کی کہ گویا وہ آپ ہی نبی ہیں جس طرف چاہا اُن کی عبارات
کو پھیر لیا اور اپنے مدعا کے موافق شرحیں لکھیں اور بیبا کی سے ہر یک جگہ مفتر یا نہ دخل دیا.موجود کو چھپایا اور معدوم کو ظاہر کیا.اور دعویٰ کے ساتھ ایسے محرف طور پر معنے کئے کہ گویا اُن
پر وحی نازل ہوئی اور وہ نبی ہیں.چنانچہ ہمیشہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ مناظرات اور مباحثات کے
وقت ایسے بیہودہ اور دور از صدق جواب عمدا دیتے ہیں کہ گویا وہ ایک نئی انجیل بنا رہے ہیں.ایسا ہی اُن کی تالیفات بھی کسی نے عیسی اور نئی انجیل کی طرف رہبری کر رہی ہیں اور وہ جھوٹ
بولنے کے وقت ذرہ ڈرتے نہیں اور چالا کی کی راہ سے کروڑ با کتابیں اپنے اس کا ذبانہ دعوے
کے متعلق بنا ڈالیں گویا وہ دیکھ آئے ہیں کہ حضرت عیسی خدائی کی کرسی پر بیٹھے ہیں.اور مھدائی
کا اس طرح پر دعویٰ کیا کہ خدائی کاموں میں حد سے زیادہ دخل دے دیا اور چاہا کہ زمین و آسمان
میں کوئی بھی ایسا بھید مخفی نہ رہے جو وہ اُس کی تہ تک نہ پہنچ جائیں اور ارادہ کیا کہ خدا تعالیٰ کے
841
Page 850
سارے کاموں کو اپنی مٹھی میں لے لیں اور ایسے طور سے خدائی کی گل اُن کے ہاتھ میں آجائے
کہ اگر ممکن ہو تو سورج کا غروب اور طلوع بھی انہیں کے اختیار میں ہی ہو اور بارش کا ہونا نہ ہونا
بھی ان کے اپنے ہاتھ کی کارستانی پر موقوف ہو اور کوئی بات ان کے آگے انہونی نہ رہے.اور
دعوی خدائی اور کیا ہوتا ہے.یہی تو ہے کہ خدائی کاموں میں اور خدا تعالیٰ کی خاص قدرتوں میں
ہی دست اندازی کریں اور یہ شوق پیدا ہو کہ کسی طرح اس کی جگہ بھی ہم ہی لے لیں.وہ لوگ جو احادیث مسیح موعود اور احادیث متعلقہ دجال پر حرف زنی کرتے ہیں اُن کو اس
مقام میں بھی غور کرنی چاہئے کہ اگر یہ پیشگوئیاں خدائے تعالیٰ کی طرف سے نہ ہوتیں اور صرف
انسان کا کاروبار ہوتا تو ممکن نہ تھا کہ ایسی صفائی اور عمدگی سے پوری ہوتیں کیا یہ بھی کبھی کسی کے
گمان میں تھا کہ یہ قوم نصاریٰ کسی زمانہ میں انسان کے خدا بنانے میں اس قدر کوششیں اور
جعلسازیاں کریں گے اور فلسفی تحقیقاتوں میں خدا کے لئے کوئی مرتبہ خصوصیت نہیں چھوڑیں
گے.دیکھو خر دجال جس کے مابین اذنین کا ستر (70) باع کا فاصلہ لکھا ہے.ریلوں کی
گاڑیوں سے بطور اغلب اکثر بالکل مطابق آتا ہے اور جیسا کہ قرآن اور حدیث میں آیا ہے کہ
اس زمانہ میں اونٹ کی سواریاں موقوف ہو جائیں گی ایسا ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ریل کی سواری
نے ان تمام سواریوں کو مات کر دیا اور اب ان کی بہت ہی کم ضرورت باقی رہی ہے اور شاید
تھوڑے ہی عرصہ میں اس قدر ضرورت بھی باقی نہ رہے ایسا ہی ہم نے بچشم دیکھا کہ در حقیقت
اس قوم کے علماء و حکماء نے دین کے متعلق وہ فتنے ظاہر کئے کہ جن کی نظیر حضرت آدم سے لے
کرتا ایں دم پائی نہیں جاتی.پس بلا شبہ نبوت میں بھی انہوں نے مداخلت کی اور خدائی میں
بھی.اب اس سے زیادہ ان احادیث کی صحت کا کیا ثبوت ہو کہ ان کی پیشگوئی پوری ہوگئی اور
قرآن کریم کی ان آیات میں یعنی إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا میں حقیقت میں اسی دجالی زمانہ
کی طرف اشارہ ہے جس کو ذرا بھی عقل ہو تو وہ سمجھ سکتا ہے اور یہ آیت صاف بتلا رہی ہے کہ وہ
قوم ارضی علوم میں کہاں تک ترقی کرے گی.( شهادة القرآن ، روحانی خزائن جلد 6 صفحہ 314 تا 317)
842
Page 851
آج جو اَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا کا زمانہ ہے یہ مسیح موعود ہی کے وقت کے لئے
مخصوص تھا.چنانچہ اب دیکھو کہ کس قدر ایجادیں اور نی کا نیں نکل رہی ہیں.ان کی نظیر پہلے کسی
زمانہ میں نہیں ملتی ہے.میرے نزدیک طاعون بھی اسی میں داخل ہے.الحکم جلد 5 نمبر 14 مورخہ 17 اپریل 1901ء صفحہ 7)
یوں تو زمین سے ہمیشہ کا نہیں نکلتی رہتی ہیں اور آتش فشاں پہاڑ پھٹتے رہتے ہیں مگر اب
خصوصیت سے ان زلزلوں کا آنا اور زمین کا الٹنا یہ آخری زمانہ کی علامتوں سے ہے اور آخرجت
الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا اسی کی طرف اشارہ ہے.زمانہ بتلا رہا ہے کہ وہ ایک نئی صورت اختیار کر رہا
ہے اور اللہ تعالیٰ خاص تصرفات زمین پر کرنا چاہتا ہے.( البدر جلد اول نمبر 4 مورخہ 21 نومبر 1902ء صفحہ 30)
ہمارے اصول میں تو یہ لکھا ہے کہ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَةُ اب اس کا اثر تم
خود سوچ لو گے کیا پڑے گا.یہی کہ انسان اعمال کی ضرورت کو محسوس کرے گا اور نیک عمل
کرنے کی سعی کرے گا.برخلاف اس کے جب یہ کہا جاوے گا کہ انسان اعمال سے نجات
نہیں پاسکتا تو یہ اصول انسان کی ہمت اور سعی کو پست کر دے گا اور اس کو بالکل مایوس کر کے
بے دست و پا بنا دے گا.جو اعمال کی ضرورت نہیں سمجھتا وہ سخت ناعاقبت اندیش اور نادان ہے.قانونِ قدرت میں
اعمال اور ان کے نتائج کی نظیریں تو موجود ہیں کفارہ کی نظیر کوئی موجود نہیں.مثلاً بھوک لگتی
ہے تو کھانا کھا لینے کے بعد وہ فرو ہو جاتی ہے.یا پیاس لگتی ہے پانی سے جاتی رہتی ہے.تو
معلوم ہوا کہ کھانا کھانے یا پانی پینے کا نتیجہ بھوک کا جاتے رہنایا پیاس کا بجھ جانا ہوا.مگر یہ تو
نہیں ہوتا کہ بھوک لگے زید کو اور بکر روٹی کھائے اور زید کی بھوک جاتی رہے.اگر قانون
قدرت میں اس کی کوئی نظیر موجود ہوتی تو شاید کفارہ کا مسئلہ مان لینے کی گنجائش رکھتا.لیکن
جب قانونِ قدرت میں اس کی کوئی نظیر ہی نہیں ہے تو انسان جو نظیر دیکھ کر ماننے کا عادی ہے
اسے کیوں کر تسلیم کر سکتا ہے.عام قانونِ انسانی میں بھی تو اس کی نظیر نہیں ملتی.کبھی نہیں دیکھا
843
Page 852
گیا کہ زید نے خون کیا ہو اور خالد کو پھانسی ملی ہو.غرض یہ ایک ایسا اصول ہے جس کی کوئی
نظیر ہرگز موجود نہیں.میں اپنی جماعت کو مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ ضرورت ہے اعمالِ صالحہ
کی.خدا تعالیٰ کے حضور اگر کوئی چیز جاسکتی ہے تو وہ یہی اعمالِ صالحہ ہیں.الحکم جلد 5 نمبر 28 مورخہ 31 جولائی 1901ء صفحہ 2)
خدا تعالیٰ ہدوں کسی نیکی ، دعا اور التجا اور بڑوں تفرقہ کا فرومومن کے ہر ایک کی پرورش
فرما رہا ہے اور اپنی ربوبیت اور رحمانیت کے فیض سے سب کو فیض پہنچا رہا ہے پھر وہ کسی کی
نیکیوں کو کب ضائع کرے گا.اس کی شان تو یہ ہے مَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ.جوزرہ
بھی نیکی کرے اس کا بھی اجر دیتا ہے اور جو ذرہ بدی کرے گا اس کی پاداش بھی ملے گی.یہ ہے
قرض کا اصل مفہوم جو اس آیت سے پایا جاتا ہے.چونکہ اصل مفہوم قرض کا اس سے پایا جاتا تھا
اس لئے یہی کہ دیا مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا ( البقرة 246) اور اس کی تفسیر
اس آیت میں موجود ہے مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ -
حضرت
خلیفتہ امسیح الاول رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:
حکم جلد 5 نمبر 21 مورخہ 10 جون 1901، صفحہ 3)
زُلْزِلَتِ لأَرْضُ زِلْزَالَهَا سے مراد ہے کہ خوب زور شور کی جنبش اہل ارض میں پیدا ہوگی.در اصل اس سورۃ شریفہ کے الفاظ سورۃ القدر کے بیان کے مفسر ہیں.سورۃ القدر میں فرمایا
تها تَنَزَّلُ الْمَلَئِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهم (آيت 5) یعنی قابل قدر زمانہ میں فرشتوں کا
نزول کثرت سے ہو گا.اور الروح جو فرشتوں کے سردار ہیں ان کا بھی نزول ہوگا.اس جگہ آیت
میں أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا فرما کر یہ ظاہر فرمایا کہ فرشتوں ہی کی تحریکات سے اہلِ
ارض زمین سے ہر قسم کے انتقال باہر نکال دیں گے.یہ اثقال معدنیات کی قسم سے بھی ہیں اور علوم و فنون کے قسم سے بھی ہیں.جس قدر معدنیات
اس وقت میں نکلے اور نکل رہے ہیں.اس کی نظیر اگلے زمانہ میں پائی نہیں جاتی.اور جس قدر علوم
844
Page 853
وفنون اہلِ ارض کے ہاتھوں سے ملائکہ اللہ کی تحریکات سے اب ظاہر ہورہے ہیں.اس کی بھی
نظیر سابقہ زمانہ میں پائی نہیں جاتی.چوتھی آیت میں جو قَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا ہے اس سے
زیادہ تر رجحان اسی بات کا معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعات قبل از قیام ساعت دنیا میں ہی ہونے
والے ہیں.کیونکہ انسان اس کا استعجاب سے مالھا کہنے دنیوی روز افزوں ترقیات و عجائبات
کے ظہور کی وجہ سے ہوگا.آخر میں بعث بعد الموت کے وقت تو تمامی امور سب پر حق الیقین کے
طور پر کھل جاویں گے.اس وقت انسان تعجب کا کلمہ نہیں کہے گا بلکہ يُلَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَياتي
(الفجر 25) کہے گا.اہلِ ارض جس قدر اپنے اخبار اس وقت شائع کر رہے ہیں وہ ظاہر ہے.جس قدر باریک
در بار یک علوم وفنون اہل ارض اس وقت ظاہر کر رہے ہیں یہ ملائکۃ اللہ ہی کی تحریک کے
نتائج ہیں.یہ ایسی ہی وحی ہے جیسے کہ شہد کی مکھی ( نحل ) کی وحی.وحی کے معنی حرف لطیف
، رموز و اشارات و کنایات کے ہیں.حمد اس آیت پر اعتراض کرتے ہوئے ایک آریہ نے اعتراض کیا کہ :
زمین باتیں کرے گی.سورج کیوں نہ کریں گے.ستارے کیوں خاموش ہیں.الجواب : اول تو سورج اور چاند کی خاموشی کا ذکر نہیں جو آپ کو اس پر تعجب ہوا.دوم : ستارے بھی تمہارے دیانند کے اعتقاد میں زمین ہی ہیں.پس ان کی خاموشی بھی
ثابت نہیں.کیونکہ وہ بھی زمین ہیں یا زمین کی طرح ہیں.پس جیسے یہ باتیں کرے گی.وہ بھی
باتیں کریں گے.سوم: یہ تا تستھ اورپارہی ہے.اگر تم کو اس کی سمجھ نہیں تو پڑھو.ستیارتھ پرکاش 254اہم
برہم اسمی ارتھ میں لکھا ہے.اس موقعہ پر تا تستھ او پار ہی (استعاره ظرف ومظروف) کا استعمال
ہے.جیسے: (منچا گری شرتنا ) منچ پکارتے ہیں.چونکہ منچ جڑ ہیں.ان میں پکارنے کی طاقت
نہیں.اس لئے منچ کے جاگزیں آدمی پکارتے ہیں.پس اسی طرح اس موقع پر سمجھنا چاہئے.845
Page 854
چہارم : تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا (الزلزال 6.5) بیان کرے گی زمین اپنی
خبریں اس لئے کہ تیرے رب نے اسے وحی کے ذریعہ حکم کیا ہے.پس ہمہ سارے ( القادر ) سرب شکستیمان ( الغنی القادر ) جو دوسرے کا محتاج نہیں.اگر وہ
زمین کو فرمادے کہ تو بیان کر تو کیا وجہ ہے کہ پھر بیان نہ ہو سکے؟ تم بھی تو قومی خداداد سے ہی
بولتے ہو.زمین بھی تو قوی خداداد سے بول سکتی یا بیان کرسکتی ہے.محدث میں یہ ضرور نہیں کہ ہماری تمہاری طرح پنجابی یا اردو بولے.ہر ایک کے مناسب
حال ہوا کرتا ہے.پھر الفاظ کی ضرورت بھی نہیں.ایک لسان الحال اور ایک لسان الافعال بھی
ہوتی ہے.اب تم خود سمجھ لو کہ زمین کی لسان کس نوع کی ہے جس سے وہ بولے گی.اور ظرف
ومظروف کے استعارہ پر کیوں تم خود سمجھ نہیں سکتے.( نور الدین طبع ثالث 117 )
فَمَن يَعْمَلُ مِفْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ
پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں آیتوں کو جَامِعَةٌ فَاذْةٌ فرمایا ہے.ہر نیکی بدی
تولنے کیلئے یہ کانٹے کی میزان ہے.مثقال ترازو کے پٹے کے وزن کا نام ہے اور ذرہ بہت کم
مقدار چیز ہے.جزا و سزا بھی انسان کو ہر وقت ملتی رہتی ہے.اگر غور کرتا رہے تو بات سمجھ آتی
ہے کہ لازمی عمل کی یہ جز املی اور فلاں کی یہ.نامعہ اعمال کے جزاوسزا کا حال بھی آنکھ کے بند
ہونے پر معلوم ہو جائے گا.موت کی کوئی خبر نہیں اس لئے ضروری ہے کہ ہر وقت مسلمان بنے رہو.یہ مت سمجھو
کہ چھوٹے سے چھوٹے عمل کی کیا ضرورت ہے اور وہ کیا کام آئے گا.نہیں.خدا تعالیٰ کسی
کے فعل کو ضائع نہیں کرتا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (الزلزال8)
ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ میں جب کافر تھا تو اللہ کی راہ
میں خیرات کیا کرتا تھا.کیا اس خیرات کا بھی کوئی نفع مجھے ہوگا.فرمایا أَسْلَمْتَ عَلَى مَا
اسلفت تیری وہی نیکی تو تیرے اس اسلام کا موجب ہوئی.خدا تعالیٰ پر سچا ایمان لاؤ اور اس
846
Page 855
کی سچی فرماں برداری کے نمونے سے ثابت کرو.ٹھیک یاد رکھو.کہ ہر نیک بیچ کے پھل
نیک ہوتے ہیں.بُرے بیج کا درخت بُرا پھل دے گا.گندم از گندم بروید جو ز جو از مکافات عمل غافل مشو
(ماخوذ از حقائق الفرقان زیر سورۃ الزلزال )
حضرت خلیفہ اسیح الثانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
زلزال کے معنی بلانے خوف زدہ کرنے اور ہوشیار اور چوکس کرنے کے ہیں.ان
معنوں کے رُو سے اس آیت کا یہ مفہوم ہو گا کہ جب سب کی سب زمین کو ہلا دیا جائے گا، خوف
زدہ کیا جائے گا اور ہوشیار کیا جائے گا.ان معنوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ نتیجہ لازماً نکلتا ہے کہ
اس جگہ زمین کا لفظ زمین کے معنوں میں استعمال نہیں ہوا بلکہ اہل زمین بھی اس جگہ پر مراد ہیں...اور بتایا گیا ہے کہ ایک وقت آئے گا جب سب زمین بلائی جائے گی اور اہلِ زمین بھی
بلائے جائیں گے ، خوف زدہ کئے جائیں گے اور ہوشیار کئے جائیں گے.چنانچہ جس حد تک زمین کے بلانے کا سوال ہے یہی زمانہ ہے کہ جس میں ریلوں اور
کارخانوں کی کثرت کی وجہ سے سرزمین کا نپتی رہتی ہے اور جہاں تک اہل زمین کا سوال ہے
مقابلہ کا ایسا بازار گرم ہے کہ متمدن دنیا میں چلتا ہوا انسان نظر آنا مشکل ہے.سب دوڑ رہے
ہیں.رات کو دنیا کی حالت کچھ ہوتی ہے تو صبح کو کچھ اور ہو جاتی ہے.زمین رات اور دن چلنے
والی ریلوں کی وجہ سے لرزہ براندم رہتی ہے اور دنیا کا کوئی گوشہ نہیں جہاں ریلوں اور کارخانوں
نے زمین کو جنبش نہیں دے رکھی.کبھی کارخانوں کے علاقوں میں جاؤ یاریل کی پٹڑی کے پاس
ریل کے گزرتے وقت گزرو تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ ایک زلزلہ آیا ہوا ہے.پھر لڑائی کے
سامان ایسے ایجاد ہوئے ہیں کہ اُن سے زمین ہل رہی ہے.جنگیں ایسی خطرناک صورت
اختیار کرگئیں ہیں کہ شہروں کے شہر اُڑا دئیے جاتے ہیں اور زمین میں غار پڑ جاتے ہیں.پھر
زلازل بھی ابھی کلام کے ماتحت بکثرت آرہیں ہیں اور علاقوں کے علاقہ ان سے صاف ہو
847
Page 856
گئے ہیں.پس جہاں تک زمین بلنے کا سوال ہے ان ایام میں زمین ایسی ہلی ہے کہ دنیا میں اس
کی ایسی نظیر نہیں ملتی کیونکہ پہلے صرف زلزلوں سے جو ممکن ہے بعض موجودہ زلزلوں سے بھی
بڑے ہوں زمین ہلا کرتی تھی مگر اب (1) زلزلوں سے اور متواتر زلزلوں سے اور عالمگیر زلزلوں
سے ہل رہی ہے (2) تو پوں، ہوائی جہازوں کے بموں، ڈائینا میٹ اور اب ایٹم بموں کے
ذریعے سے جو ساری دنیا اور ہر خطہ زمین پر اثر انداز ہوئے ہیں زمین ہلی ہے اور بہت بُری
طرح ہلی ہے اور یہ اشیاء پہلے زمانہ میں موجود ہی نہیں تھیں اسی زمانہ میں ایجاد ہوئی ہیں (3)
ریلوں ، زمین دوز ریلوں اور کارخانوں کی وجہ سے جو قطب شمالی سے قطب جنوبی تک اور مغرب
سے مشرق تک پھیلے ہوئے ہیں زمین روز و شب ہل رہی ہے اور اگر یہی ترقی جاری رہی تو ملتی
چلی جائے گی.دوسرے معنے اہل زمین کے ہیں.اگر ہم دیکھیں تو وہ بھی اس طرح ہلائے گئے ہیں کہ اس سے
پہلے کبھی نہیں بلائے گے.انسانوں کے ہلنے کے یہ معنے ہوا کرتے ہیں.اؤل لوگوں میں بیداری
پیدا کی جائے.دوم لوگوں میں خوف پیدا کیا جائے.سوم لوگوں میں غیر معمولی تبدیلی پیدا ہو جو علاوہ اور
اقسام کے مندرجہ ذیل امور سے ہوا کرتی ہے (الف) سیاسیات میں تبدیلی کی وجہ سے (باء)
معاشیات میں تبدیلی کی وجہ سے (ج) مذہبیات میں تبدیلی کی وجہ سے ( د ) اخلاقیات میں تبدیلی کی
وجہ سے ( ح ) علوم میں تبدیلی کی وجہ سے ( و ) اقتصادیات میں تبدیلی کی وجہ سے.یہ سارے کے
سارے امور اہل دنیا کو بلانے کے اس زمانے میں ظاہر ہورہے ہیں.وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا
-
ثقل کے معنے بوجھ کے بھی ہوتے ہیں اور قیمتی شے کے بھی.وہ شے جس کی حفاظت کی
جائے.اسی طرح زمین کے خزانہ کو بھی نقل کہتے ہیں.ان معنوں کے رُو سے اس آیت کا مفہوم ہوگا کہ :
اول : زمین اپنے بوجھ اتار کر پھینک دے گی یعنی بادشاہتوں اور حکومت امراء کو جو غرباء پر
848
Page 857
ناقابل برداشت بوجھ ڈال رہے تھے نکال باہر کرے گی.اس زمانہ میں دنیا کے تمام ممالک
بادشاہتوں کو توڑ رہے ہیں یا ان کو ناکارہ بنا رہے ہیں اور یہ ایک ایسی بات ہے جس کی پہلے
زمانہ میں کوئی مثال ہی نہیں ملتی.(2) دوسرے معنے اس آیت کے یہ ہیں کہ مولویوں ، پادریوں اور پنڈتوں کے دباؤ سے
لوگ آزاد ہوجائیں گے.3) تیسرے معنے اثقال کے ظاہری زمین کے لحاظ سے یہ بنیں گے کہ زمین میں سے
قسم قسم کی کانیں نکل آئیں گی.چنانچہ...ہر شخص دیکھ سکتا ہے کہ زمین نے آج اپنے بوجھ باہر
نکال کر پھینک دیتے ہیں.4) آثار قدیمہ جو زمین میں چھپے پڑے تھے وہ بھی اثقال تھے اور امانت کا رنگ رکھتے تھے
جسے زمین نے اپنے پیٹ میں دبایا ہوا تھا مگر آج یہ اثقال بھی باہر نکل رہے ہیں....آج محکمہ
آثار قدیمہ زمین کو کھود کر ان تمام شہروں کو باہر نکال رہا ہے اور کئی قسم کی پرانی تہذیبوں کا
لوگوں کو علم حاصل ہو رہا ہے....بلکہ اور تو اور مردے بھی باہر نکالے جا رہے ہیں اور عجائب
گھروں میں لوگ ان کا تماشہ دیکھتے ہیں.غرض زمین کے نیچے جو چیزیں دبی ہوئی تھیں زمین
نے اُن
کا بوجھ محسوس کیا اور اس نے ان تمام چیزوں کو باہر نکال دیا.5) اگر ارض سے اہل ارض مراد لئے جائیں تو اخرجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا کے یہ معنی ہوں
گے کہ عیاشی ، آزادی اور لامذہبی وغیرہ کے وہ خیالات جن کو پہلے زمانہ میں لوگ اپنے سینوں میں
دبا کر رکھتے تھے اور ڈرتے تھے کہ اگر ہم نے ان خیالات کو ظاہر کیا تو گدی سے ہماری زبان کھینچ
لی جائے گی علی الاعلان ظاہر کریں گے.ان کے متعلق کتابیں لکھیں گے اور لوگوں سے بحثیں
کریں گے کہ صحیح خیالات یہی ہیں تمہیں بھی اپنے سابق خیالات میں تبدیلی پیدا کرنی چاہیئے.6 چھٹے معنے یہ ہیں کہ اُس زمانہ میں سائنس کی ایجادات کثرت سے ہوں گی اور زمین اپنے
چھپے ہوئے راز نکال کر رکھ دے گی.ہم دیکھتے ہیں کہ یہ علامت بھی اس زمانہ میں نمایاں طور پر
849
Page 858
پوری ہوئی ہے چنانچہ ہر سال حیرت
انگیز طور پر کئی قسم کی ایجادات ہو جاتی ہیں اور یہ سلسلہ برابر
بڑھتا جا رہا ہے.وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَالَهَا
اور انسان کہہ اُٹھے گا کہ اسے کیا ہو گیا ہے.اس دن وہ اپنی (ساری ہی پوشیدہ) خبریں
بیان کر دے گی.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زمین اپنے اثقال کو نکال باہر کرے گی یہاں تک کہ ان سب
چیزوں کو دیکھ کر انسان حیرت سے کہہ اُٹھے گا کہ مالھا.اسے کیا ہو گیا ہے اس دنیا میں کیا
کچھ راز پوشیدہ تھے جو ظاہر ہورہے ہیں اور کیا کیا چیزیں مخفی تھیں جن کو زمین اُگل رہی ہے.دوسرے معنے یہ ہو سکتے ہیں کہ الانسان سے ہر انسان مراد نہ ہو بلکہ کامل انسان مراد ہو.اس صورت میں آیت کا یہ مفہوم ہو گا کہ کامل انسان دنیا کی عریانی اور لامذہبیت کی حالت دیکھ
کر کہے گا کہ اس دنیا کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ خدا تعالیٰ سے اس قدر دور چلی گئی ہے.يَوْمَئِذٍ تُحَيثُ الخَبَارَهَا
کا یہ نیا مضمون بھی ہو سکتا ہے اور وَاخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا کی تشریح بھی ہو سکتا ہے.نے مضمون کے لحاظ سے میرے نزدیک اس کے یہ معنے ہیں کہ پیدائش زمین کے بارہ میں اس
سے پہلے دنیا کو ایک مجمل اور ناقص علم حاصل ہوگا مگر فرماتا ہے اس زمانہ میں علم سائنس جیالوجی
کی شکل میں اس قدر ترقی کر جائے گا کہ زمین کی بناوٹ اور شعاعوں اور لہروں وغیرہ کے ذریعہ
سے زمین کی پیدائش کے مسئلہ پر بہت کچھ روشنی پڑنے لگے گی گویا اخبارھا سے مراد یہ ہے
کہ زمین اپنی حقیقت اور کیفیت پیدائش کے بارہ میں بہت کچھ باتیں بتانے لگ جائے گی.یہ اس لئے فرمایا کہ علم جیالوجی کا بڑا امدار خود مٹی کی ماہیت اور اس کے رنگوں اور اس کی تہوں پر
ہے.یہ نہیں کہ کسی اور ذریعہ سے وہ ان معلومات کو حاصل کرتے ہیں بلکہ علم جیالوجی کے
ماہرین مٹی کا رنگ دیکھ کر بتا دیتے ہیں کہ اس اس قسم کے تغیرات زمین پر گزرے ہیں اس کی
تہوں سے اندازہ لگا کر بتا دیتے ہیں کہ اس پہ پر یہ شکل ہے اور اس پہ پر یہ شکل ہے جس سے
850
Page 859
یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلے فلاں تغیر واقعہ ہوا اور پھر فلاں تغیر پیدا ہوا.اسی طرح مٹیوں کے رنگوں
اور ان کی بوؤں سے اب کانوں وغیرہ کے پتہ لگانے کا علم نکل آیا ہے.اس علم کے ماہر انجینئر
پہاڑوں کی چوٹیوں پر چلے جاتے ہیں اور پتھروں کو اٹھا اٹھا کر دیکھتے یا زمین کو سونگھتے ہیں اور
بتاتے جاتے ہیں کہ یہاں فلاں قسم کی کانیں دفن ہیں.اسی طرح بجلی کی رو کے ذریعہ سے
کانوں کی اقسام اور ان کی گہرائیوں کا پتہ لیا جاتا ہے.یہ پتہ لگایا جاتا ہے کہ زمین میں کس چیز
کی کان ہے.لوہے کی ہے یا پیتل کی ہے اور پھر یہ پتہ لگایا جاتا ہے کہ وہ سو گز نیچے ہے یا دوسو
گز نیچے ہے یا چار سو گز نیچے ہے.غرض اس ذریعہ سے زمین اپنی خبریں بتا رہی ہے.وہ زمین
جو پہلے گونگی تھی اب کلام کرنے لگ گئی ہے.عام لوگ گزرتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ زمین خاموش
ہے وہ کچھ کہ نہیں رہی.لیکن ایک انجینئر گزرتا ہے تو وہ سنتا ہے کہ زمین اسے یہ کہہ رہی ہوتی
ہے کہ میرے نیچے مٹی کا تیل ہے اور وہ یہ کہ رہی ہوتی ہے کہ وہ اسی گز نیچے ہے یا یہ بتارہی
ہوتی ہے میرے نیچے سونے کی کان ہے اور یہ بھی بتارہی ہوتی ہے وہ سونے کی کان اتنی دور
ہے یا یہ بتارہی ہوتی ہے کہ میرے نیچے پتھر کا کوئلہ ہے اور یہ بھی بتا رہی ہوتی ہے کہ وہ پتھر کا
کوئلہ اتنی دور ہے.اسی طرح بتا رہی ہوتی ہے کہ میرے نیچے یورینیم یا پلاٹینیم یا فلاں دھات
ہے اور یہ بھی بتارہی ہوتی ہے کہ یہ دھاتیں اتنی گہرائیوں پر ہیں.اخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا کے جو یہ معنے بتائے گئے تھے کہ لوگ اپنے گندے خیالات بیان
کرنے لگ جائیں گے ان کے لحاظ سے اس آیت کے یہ معنے بھی ہوں گے کہ نہ صرف لوگوں
کے دیئے ہوئے خیالات اس زمانہ میں ظاہر ہونے لگ جائیں گے بلکہ اہل زمین اپنے ان
عیوب کو الم نشرح کرنے میں لذت محسوس کریں گے یا دوسروں کے عیوب شائع کرنے میں
انہیں خاص لطف محسوس ہوگا اور وہ انتہائی دلچسپی کے ساتھ اس کام میں حصہ لیں گے.چنانچہ تمام
یورپ، امریکہ بلکہ ایشیائی ممالک میں بھی آج کل ایسے اخبارات نکلتے ہیں جن کو سوسائٹی گاسپ
(society gossip) کہا جاتا ہے.یہ اخبار اس کثرت سے دنیا میں شائع ہونے لگ گئے
ہیں اور اس طرح مزے لے لے کر ان کو پڑھا جاتا ہے کہ حیرت آتی ہے.ان اخبارات کو
851
Page 860
چلانے والے بھی لاکھوں روپیہ اس بات پر خرچ کر دیتے ہیں کہ انہیں کسی بڑے شخص کے راز
معلوم ہو جائیں.خواہ وہ مرد ہو یا عورت اور پھر جب وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو جاتے
ہیں تو ان رازوں کو اخبارات کے ذریعہ شائع کیا جاتا ہے اور دنیا میں ان کی خوب
تشہیر کی جاتی
ہے.اس کے علاوہ لوگ خود اپنے شہوانی جذبات کی نسبت بالتفصیل کتب لکھنے لگ گئے ہیں
صرف قانون کی زد سے بچنے کے لئے ان کتابوں پر یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ کتابیں صرف ڈاکٹروں
اور فلاسفروں کے لئے لکھی گئی ہیں عام لوگوں کے لئے نہیں.تا کہ یہ سمجھا جائے کہ ان کتابوں کی
اشاعت محض علمی اغراض کے ماتحت کی جارہی ہے کوئی نفسانی خواہش ان کتب کی اشاعت کی
محرک نہیں ہے.ایک حدیث بھی ان معنوں کی تصدیق کرتی ہے.میں سمجھتا ہوں کہ وہ حدیث اسی زمانہ
کے بارہ میں ہے.احمد ، ترمذی اور نسائی نے روایت کی ہے ( گو الفاظ روایت احمد کے ہیں )
کہ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَرَأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ هَذِهِ الْآيَةَ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا قَالَ
اندرُونَ مَا أَخْبَارُهَا قَالُوا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّ أَخْبَارَهَا أَنْ تَشْهَدَ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ
و آمَةٍ بِمَا عَمِلَ عَلَى ظَهْرِهَا أَنْ تَقُولَ عَمِلَ كَذَا وَكَذَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا فَهَذِهِ أَخْبَارُهَا.یعنی حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم عالم نے یہ آیت پڑھی کہ
يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا پھر آپ نے فرمایا آتَدْرُونَ مَا أَخْبَارُهَا اے میرے صحابہ کیا تم
جانتے ہو کہ اس کی اخبار کیا ہیں ؟ قَالُوا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول
ہی بہتر جانتے ہیں.قَالَ فَإِنَّ أَخْبَارَهَا أَنْ تَشْهَدَ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ وَ آمَةٍ بِمَا عَمِلَ عَلَى
ظهْرِهَا.اس کی خبریں یہ ہیں کہ وہ ہر انسان یعنی ہر مرد اور عورت کے متعلق یہ بیان کرے گی کہ
اس نے کیا کیا ہے.آنْ تَقُولَ عَمِلَ كَذَا وَ كَذَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا.وہ یہ کہے گی کہ اس نے
فلاں دن یہ کام کیا ہے اور فلاں دن یہ کام کیا.چونکہ اس آنے والے دن کے بارہ میں محدثین کو
علم نہ تھا انہوں نے اسے قیامت پر لگایا ہے حالانکہ جہاں تک میں سمجھتا ہوں یہ حدیث اسی
852
Page 861
زمانہ کے متعلق ہے.اسی زمانہ میں اس قسم کے اخبارات شائع ہورہے ہیں جن میں لوگوں
کے تمام عیوب بیان کئے جاتے ہیں اور لوگ ان اخبارات کو بڑے شوق سے پڑھتے ہیں.میں سمجھتا ہوں حدیث میں اسی طرف اشارہ ہے.مفسرین نے اسے غلطی سے قیامت پر
چسپاں کر دیا ہے حالانکہ قیامت کے ذکر میں قرآن کریم میں یہ
کہیں بیان نہیں کیا گیا کہ اس روز
زمین بھی کلام کرے گی.یہ تو آتا ہے کہ ہاتھ بولیں گے یا پاؤں بولیں گے اور وہ انسان کے
خلاف شہادت دیں گے مگر یہ کہیں ذکر نہیں آتا ہے کہ اس روز زمین بھی بولے گی.لیکن مسیح موعود کے زمانہ کے متعلق بالوضاحت احادیث میں ذکر آتا ہے کہ اس وقت زمین
کلام کرے گی.چنانچہ حدیث میں آتا ہے مسیح موعود کے زمانہ میں وہ پتھر جس کے پیچھے کافر چھپا
ہوا ہوگا بول اٹھے گا اور کہے گا اے نبی اللہ یہ کا فرچھپا ہوا ہے.غرض زمین کے بولنے کا حدیثوں
میں جہاں بھی ذکر آتا ہے مسیح موعود کے زمانہ کے متعلق ہے اور قرآن کریم میں جہاں قیامت
کے دن شہادت دینے کا ذکر آتا ہے وہاں ہاتھوں اور پاؤں کے بولنے کا تو ذکر آتا ہے مگر زمین
کا نہیں.اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت موجودہ زمانہ کے متعلق ہے اور اس میں اللہ
تعالیٰ کی طرف سے یہی خبر دی گئی ہے کہ لوگ اپنے گند اخباروں میں ظاہر کریں گے.کتابوں
اور ڈائریوں میں ان کو شائع کریں گے اور خوش ہوں گے کہ انہوں نے بہت بڑا کارنامہ
سرانجام دیا ہے.گویا جن امور کو لوگ پہلے چھپایا کرتے تھے ان کو مزے لے لے کر بیان
کریں گے اور شرم اور حیا کا مفہوم اس زمانہ میں بالکل بدل جائے گا.گزشتہ تاریخ پر غور کر کے دیکھ لو اس کی نظیر پہلے کسی زمانہ میں نہیں ملے گی.یہی وہ زمانہ
ہے جس میں یہ زلزلہ عظیمہ آیا اور جس میں اللہ تعالیٰ کی یہ پیشگوئی بڑی شان سے پوری ہوئی کہ
يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا.853
Page 862
بان رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا
وحی کے معنے (1) کسی کام پر مبعوث کرنا (2) دل میں بات ڈالنا ( 3 ) اشارے سے
بات سمجھانا (4) کسی پیغامبر کی معرفت پیغام بھیجنا (5) لکھنا (6) دوسروں سے چھپا کر بات
کرنا اور (7) حکم دینا کے ہیں.قرآن کریم میں وحی کا لفظ اس مقام کے سوا پینسٹھ دفعہ استعمال ہوا ہے اور سب جگہ الی کا صلہ
آیا ہے.پانچ مقامات اور ہیں جہاں یا تو یہ لفظ مجہولاً استعمال ہوا ہے یا حذف صلہ کے ساتھ
استعمال ہوا ہے.حذف صلہ سے میری مراد یہ ہے کہ وہاں موحی الیہ کا ذکر نہیں کیا گیا.اس
لئے ان مقامات پر قیاس نہیں کیا جاسکتا.بہر حال ان سب استعمالات کی موجودگی میں جبکہ
قرآن کریم میں پینسٹھ دفعہ یہ لفظ الیٰ کے صلہ کے ساتھ استعمال ہوا ہے اور اس امر کو دیکھ کر
احادیث میں بھی جہاں یہ لفظ استعمال ہوا ہے الیٰ کے ساتھ استعمال ہوا ہے.لام کا صلہ استعمال
نہیں کیا گیا.یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ اس جگہ بھی تھا سے یہ مراد نہیں کہ زمین کی طرف وحی کی
بلکہ لام کے معنی فی کے ہیں یعنی زمین کے حق میں وحی کی اور جس کی طرف وحی ہوئی اس کے
ذکر کو چھوڑ دیا گیا ہے.اگر زمین کی طرف وحی کرنا مراد ہوتا تو محاورۃ قرآن و محاورۂ حدیث کو
مدنظر رکھتے ہوئے اس جگہ اوحى إِلَيْهَا آتا، أوحى لھا نہ آتا.یہ بات ہر شخص جو قرآن کو
پڑھنے والا ہے جانتا ہے کہ قرآن کریم رسول کریم علی الم پر نازل ہوا ہے اس لئے گو یہاں
موحی الیہ محذوف ہے اور یہ ذکر نہیں کیا گیا کہ وحی کس کو ہوئی لیکن اس بات کا سمجھنا مشکل
نہیں کہ اس جگہ رسول کریم ملی کا ہی ذکر کیا جارہا ہے اور بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا کے معنے یہ ہیں
کہ أوحى الله إلى مُحَمد ﷺ لَهَا.یعنی ان عظیم الشان تغیرات پر تمہیں کوئی استعجاب نہیں ہونا
چاہئے.یہ سب تغیرات اس لئے ہوں گے کہ اس کے ان تغیرات کے متعلق پہلے سے قرآن
کریم میں پیشگوئی موجود ہوگی.گویا یہ آیت زمانہ بعد نزول کے لوگوں کو مد نظر رکھ کر ہے.پان
ربَّكَ أوحى لَهَا اللہ تعالیٰ اس بارہ میں پہلے سے خبر دے چکا ہے اور اس نے کہہ دیا ہے کہ ایسا
854
Page 863
ضرور ہو کر رہے گا.پس چونکہ اللہ تعالیٰ اپنی وحی کے ذریعہ یہ خبر دے چکا ہے کہ اخرجت
الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا.اہل زمین اپنے گند ظاہر کر دیں گے اس لئے اب یہ اٹل فیصلہ ہے اور خدائی
تقدیر کا ہاتھ اس کو بہر حال پورا کر کے رہے گا.کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کسی بات کی اپنی وحی کے ذریعہ
خبر دے دے اور اسے کسی مامور کی سچائی کی علامت قرار دے دے تو پھر وہ کبھی ٹلا نہیں کرتی.آوحی کا صلہ ہمیشہ الی استعمال ہوتا ہے مگر اس جگہ آؤحی کے بعد لام استعمال کیا گیا ہے.ایسا کیوں ہوا ہے؟ مفسرین نے اس کا یہ جواب دینے کی کوشش کی ہے کہ بعض قبائل عرب
میں الی کی بجائے لام بھی بطور صلہ استعمال ہوتا ہے.مگر ہم اس توجیہ کو درست تسلیم نہیں
کر سکتے.قرآن کریم میں پینسٹھ جگہ وحی کا لفظ آیا ہے اور ہر جگہ الی کا صلہ ہی استعمال ہوا ہے اس
لئے کوئی وجہ نہیں کہ یہاں الی کی بجائے لام کے صلہ کا جواز نکالا جائے.بعض اور مفسرین
نے اس جواب کی غلطی کو محسوس کیا ہے اور انہوں نے اس کے معنے یہ کئے ہیں کہ اوحی الی
الْمَلَائِكَةِ لَهَا یعنی جس کی طرف وحی کی گئی ہے اس کے ذکر کو محذوف تسلیم کیا ہے.یہ توجیہ
درست ہے لیکن میرے نزدیک یہاں آؤ حى إلى الْمَلَئِكَةِ مراد نہیں بلکہ أَوْحَى إِلَى رَسُولِ اللهِ
مراد ہے اور معنے یہ ہیں کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلیم کو وحی کے ذریعہ یہ خبریں
دے رکھی ہیں اس لئے اب ایسا ضرور ہو کر رہے گا.یہ بات رک نہیں سکتی.ہم نے اپنی وحی میں
یہ خبر دے دی ہے کہ اس زمانہ میں جب مسیح موعود آئے گا اور جو ہمارے رسول کی دوسری بعثت
کا زمانہ ہوگا یہ علامات رونما ہوں گی.پس بیشک اور باتیں ٹل سکتی ہیں مگر یہ علامت کبھی ٹل
نہیں سکتی کیونکہ جس چیز کو کسی مامور کی شناخت کے متعلق بطور علامت قرار دے دیا جائے وہ
کبھی ٹلا نہیں کرتی.اس اصول کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی کتب میں
بیان فرمایا ہے اور لکھا ہے کہ بے شک انداری خبریں ٹل جایا کرتی ہیں مگر وہ انداری خبریں جو
اللہ تعالیٰ کے کسی مامور کی علامت کے طور پر بیان ہوئی ہوں
کبھی نہیں ٹلتیں.بلکہ وہ اسی طرح
پوری ہوتی ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے خیر کے امور پورے ہوتے ہیں.855
Page 864
حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس آیت کے ایک اور معنے بھی فرمایا کرتے تھے جو
میں نے خود آپ کی زبان سے سنے ہیں.آپ فرماتے تھے بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا سے مراد یہ
ہے کہ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى إِلَى اِمَامِ الزَّمَانِ یعنی جس کی طرف وحی کی گئی ہے اس سے مراد
آنحضرت علی یہ بھی ہیں اور امام الزمان بھی جس کی طرف اس وقت کہ ان پیشگوئیوں کے پورا
ہونے کا وقت قریب ہوگا دوبارہ وحی کی جائے گی.آپ کا مطلب یہ تھا کہ دنیا میں مختلف قسم
کے زلازل کے ظہور کے متعلق جو خبریں آپ کو دی گئی تھیں ان کی طرف بھی اس میں اشارہ
ہے.چونکہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ یہ زلازل پہلے کیوں نہیں آئیں گے.اس وقت کیوں آئیں
گے جب مسیح موعود کی بعثت ہوگی؟ اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ یہ زلازل
اس وقت اس لئے آئیں گے کہ یہ اس کی سچائی کی علامت قرار دئیے گئے ہیں.چنانچہ جب
مسیح موعود آئے گا اور اس علامت کے ظہور کا زمانہ قریب آ جائے گا اللہ تعالیٰ پھر اپنا الہام
نازل کر کے مسیح موعود کو خبر دے گا کہ لو وہ زمانہ اب آ گیا جس کی ہم قرآن کریم میں خبر دے
چکے تھے.اس طرح تکرار الہام نہ صرف زمانہ زلازل کے قرب پر دلالت کرے گا بلکہ اس
بات کا بھی ثبوت ہوگا کہ یہی وہ مامور ہے جس کی سچائی ثابت کرنے کیلئے زلازل کا ظہور ہورہا
ہے.پس اس وحی کے بعد دنیا میں زلازل کا سلسلہ اس لئے شروع ہوگا تا کہ یہ زلازل امام
زمان کی سچائی کا ثبوت قرار پائیں اور دنیا غور کرے کہ اگر وہ خدا تعالیٰ کا مامور نہیں تو آخر کیا
وجہ ہے کہ جب کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ بڑے بڑے زلازل سے دنیا کا
نقشہ پلٹنے والا ہے اس نے ان تاریک دنوں کی خبریں دی اور پھر وہ حرف بحرف پوری
ہوگئیں.غرض موحی راکیہ دونوں ہیں.رسول کریم علی بھی اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام
بھی.رسول کریم ملایم وحی اول کے لحاظ سے اور مسیح موعود وحی ثانی کے لحاظ سے.إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَاخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقالَهَا کی پہلی وحی چونکہ رسول کریم
پر نازل ہوئی اور در حقیقت آپ کی صداقت کے اظہار کیلئے ہی قیامت تک تمام
856
Page 865
نشانات کا ظہور ہوگا اور جو شخص بھی لوگوں کی ہدایت کیلئے کھڑا ہوگا وہ بہر حال آپ کا غلام ہوگا.اس لئے اول مصداق اس آیت کے رسول کریم علیہ عالم ہیں مگر چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس زلزلہ
عظیمہ کے اظہار کو روکے رکھا جب تک کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر دوبارہ الہام
نازل نہ ہوا تا وہ بات پوری ہو جو لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوْا مِنْ أَهْلِ الْكِتَبِ وَالْمُشْرِكِيْنَ
مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ رَسُولٌ مِن اللہ میں بیان کی گئی تھی اور بتایا گیا تھا کہ محمد
رسول الله علیم اپنے مثیل کے ذریعہ ایک اور زمانہ میں بھی ظاہر ہوں گے اور دوبارہ لوگوں کو
کفر و شرک کی تاریکیوں سے نجات دیں گے اس لئے اس آیت کے دوسرے مصداق حضرت
مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مقدر کیا ہوا تھا کہ یہ زلزلہ اس وقت تک
نہیں آئے گا جب تک دوبارہ اس شخص پر وحی نازل نہ ہو جائے جو مثیل ہوگا آ نحضرت علایم
کا اور جس کی سچائی کے لئے اسے علامت قرار دیا گیا ہے.پس موحی الیه آنحضرت علی
بھی ہیں اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بھی.اور بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا میں ان دونوں
وجیوں کی طرف اشارہ ہے.وحی اوّل کی طرف اس لئے کہ وہ بادی ہے اور وحی ثانی کی طرف
اس لئے کہ وہ مثال کے رنگ میں وہی جلوہ دوبارہ ظاہر کرنے والی ہے جو آنحضرت ملایم
کے ذریعہ ظاہر ہوا.يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ اشْتَاتًا لِيُرَوُا أَعْمَالَهُمْ
اشتاتا کے معنے ہیں متفرقین یعنی گروہ در گروہ.مفسرین نے اس کے معنے آخرت کے لحاظ سے کئے ہیں.چونکہ انہوں نے تمام سورۃ کو
آخرت پر چسپاں کیا ہے اس لئے اس کے معنے بھی انہوں نے نیک و بد جنتی و دوزخی اور سفید و
سیاہ کے کئے ہیں.اسی طرح وہ آشتانا کے معنے دائیں طرف والے اور بائیں طرف والے
کے کرتے ہیں.میں چونکہ اسے آخری زمانہ کے متعلق سمجھتا ہوں جس میں رسول کریم علی ایم کی بعثت ثانیہ
857
Page 866
مقدر تھی اس لئے میں اس کے یہ معنے کرتا ہوں کہ اس وقت جتھہ بندی زوروں پر ہوگی.اور
پارٹی بازی بہت ہوگی.يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا.یہ ایک خاص علامت ہے جو پہلے کسی زمانہ میں رونما
نہیں ہوئی.صرف موجودہ زمانہ ہی ایسا ہے جس میں یہ علامت نمایاں طور پر نظر آتی ہے.پہلے
زمانوں میں صرف منفرد کوششیں کی جاتی تھیں.اجتماع اور اتحاد کا رنگ ان میں مفقود تھا.مگر
قرآن کریم اس جگہ یہ خبر دیتا ہے کہ آخری زمانہ میں یہ اختلافات جتھہ بندی کی شکل اختیار کر
لیں گے اور پارٹی سسٹم بہت ترقی کر جائے گی.اور لوگ یہ پارٹی بازی اس لئے کریں گے
ليروا أَعْمَالَهُمْ کہ اپنے اعمال کا نتیجہ دیکھیں.یعنی انہیں یقین ہوگا کہ جتھہ بندی سے کام
کرنے کے نتائج اچھے نکلتے ہیں.اگر جتھہ بندی نہیں ہوگی تو ہمارے کام کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے
گا.فرماتا ہے يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا اس دن انفرادی جدو جہد کی بجائے تمام لوگ
جتھہ بندی کر کے آئیں گے اور اس لئے آئیں گے لیروا اعمالهُمْ تا کہ ان کے اعمال ان کو
دکھائیں جائیں.یعنی ان کے فعل کا نتیجہ نکل آئے.انفرادی رنگ میں کوشش کرنے سے
چونکہ ہر شخص کی طاقت ضائع چلی جاتی ہے اور کوئی اچھا نتیجہ برآمد نہیں ہوتا اس لئے وہ اس دن
جقہ بندی اور پارٹی سسٹم کی طرف مائل ہو جائیں گے اور متحدہ محاذ قائم کر کے اپنے مطالبات
پیش کریں گے تاکہ ان کی آواز میں اثر پیدا ہو اور وہ مطالبات جو ان کی طرف سے پیش کئے
جائیں ان کو قبول کرنے کے لئے دوسرے لوگ تیار ہوں.اس جگہ ھند کی ضمیر اسی لئے لائی گئی ہے کہ اس میں متعدد گروہوں کی طرف اشارہ کیا گیا
ہے اور بتایا گیا ہے کہ ہر گروہ اپنے اپنے حقوق کے متعلق جدو جہد کرے گا.چنانچہ آج دنیا
میں ہزاروں پارٹیاں بن رہی ہیں اور کتابوں میں صاف طور پر لکھا جاتا ہے کہ پہلے زمانوں میں
ناکامی کی بڑی وجہ یہی تھی کہ مل کر کام نہیں کیا جاتا تھا اب ہم مل کر کام کریں گے اور اپنی آواز کو
858
Page 867
زیادہ سے زیادہ مؤثر اور نتیجہ خیز بنانے کی کوشش کریں گے.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ٹھیک
ہے ہمارا بھی یہی منشاء تھا کہ انفرادی کوشش کی جگہ اس دن قومی کوشش ہو تا خوب اچھی
طرح خیر وشر کا فرق ظاہر ہو جائے.اس جگہ لیروا اعمالھم میں جہاں بندوں کی طرف سے
اپنے حقوق کے لئے جدو جہد شروع ہونے کا ذکر ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ان کی
تائید کا اشارہ پایا جاتا ہے یعنی جہاں وہ اپنے اپنے دائرہ اور اپنے اپنے رنگ میں کوشش
کر رہے ہوں گے وہاں خدا تعالیٰ بھی کوشش کر رہا ہوگا.فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَ ايَّرَهُ - وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرِّ ايْرَهُ
پھر جس نے ایک ذرہ کے برابر ( بھی ) نیکی کی ہوگی وہ اس (کے نتیجہ ) کو دیکھ لے گا.اور جس نے ایک ذرہ کے برابر (بھی) بدی کی ہوگی وہ اس (کے نتیجہ ) کو دیکھ لے گا.فرماتا ہے لوگوں کے اکٹھا کام کرنے سے ہمارے اس قانون کی سچائی ثابت ہوگی کہ جو
شخص ایک ذرہ بھر بھی عمل خیر دوسروں کے ساتھ مل کر کرے گا وہ اس کا نتیجہ دیکھ لے گا اور جو
شخص ایک ذرہ بھر بھی عمل شر دوسروں کے ساتھ مل کر کرے گا وہ اس کا نتیجہ دیکھ لے گا.یعنی
اس زمانہ میں چونکہ ہر شخص اپنی پارٹی سے مل کر کام کرے گا اس لئے ہر قسم کے کام کا نتیجہ نمایاں
نکلے گا.کیونکہ مشترک کام ذرہ ذرہ پل کر بھی پہاڑ ہو جاتا ہے.الگ کیا ہوا کام ذرہ کے مطابق
ہو تو اس کا نتیجہ محسوس کرنا مشکل ہوتا ہے مگر وہ ذرہ بھر کام جو قوم کے ساتھ مل کر کیا ہو چھپ
نہیں سکتا کیونکہ دوسروں کے ذروں سے مل کر وہ پہاڑ بن جاتا ہے.پس فرماتا ہے چونکہ اس دن
پارٹیاں مل کر کام کریں گی ہر کام کا نتیجہ نمایاں نظر آئے گا اور عمل کا ایک ذرہ بھی ضائع نہیں ہوگا.غرض يَصْدُرُ النَّاسُ اشتاتا نے یعنی ایک دوسرے کے بالمقابل ایک ایک کر کے نکلنے
کی جگہ پارٹی پارٹی بن کر نکلنے نے وہ نمونہ دکھایا کہ دنیا نے کبھی نہ دیکھا تھا.یہ پارٹیاں خیر کا
کام کرتی ہیں تو وہ بھی ایک عظیم الشان شکل میں ظاہر ہوتا ہے اور اگر برا کام کرتی ہیں تو وہ بھی
ایک مہیب اور دل پر کپکپی نازل کر دینے والی شکل میں نظر آتا ہے.چونکہ مومن بھی اس دن مل
859
Page 868
کر کام کریں گے اس لئے ان کے خیر کے نتائج بھی بڑے شاندار ہوں گے بلکہ چونکہ خیر کا
دس گنا اجر ہے اس لئے ان کے خیر کے نتائج شر کے نتائج پر غالب آجائیں گے.یہ معنے تو ترتیب کے لحاظ سے ہوئے.حمد یوں بھی اپنی ذات میں یہ آیت نہایت اہم ہے.رسول کریم ہال کی اس آیت کی نسبت
فرماتے ہیں ( آپ سے گدھوں کے بارہ میں پوچھا گیا کہ ان کے رکھنے کا کیا ثواب ہے تو
فرمایا مَا أَنْزَلَ اللهُ فِيهَا شَيْئًا إِلَّا هَذِهِ الْآيَةَ الْفَاذَةَ الْجَامِعَةَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا
يرَهُ.وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرِّ ايْرَةُ فَاذَة کے معنے ہیں منع کرنے والی اور جامعہ کے
معنے ہیں سمیٹنے والی.یعنی رسول کریم علیہ نے فرمایا اس بارہ میں مجھ پر اللہ تعالی کی طرف سے
یہ ایک فازہ اور جامعہ آیت نازل ہو چکی ہے کہ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ.وَمَنْ
يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا ترہ یعنی ہر چیز جس کو نکالنا مقصود ہے اس کو اس آیت کے ذریعہ
نکال دیا گیا ہے اور ہر چیز جس کو سمیٹنا مقصود ہے اس کو اس آیت کے ذریعہ سمیٹ لیا گیا
ہے.گویا یہ آیت جزائے خیر وشر کے متعلق ایک جامع مانع قاعدہ پر مشتمل ہے.جزائے خیر
اور جزائے شر سے تعلق رکھنے والی کوئی بات نہیں جو اس میں بیان نہ کی گئی ہو.اسلام نے بنی نوع انسان کو یہ مژدہ جانفزا سنایا کہ اس عالم کا ایک خدا ہے جس کی نگاہ
میں انسان کا ہر چھوٹے سے چھوٹا کام آجاتا ہے.اگر کوئی عمل خیر کرتا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے
علم میں ہوتا ہے اور اگر کوئی عمل شر کرتا ہے تو بھی خدا تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے.تم مت سمجھو کہ
تمہارے اعمال ضائع چلے جائیں گے اور ان کا کوئی نتیجہ رونما نہیں ہوگا.اگر دنیا میں تمہارے
اعمال خیر مخفی رہے ہیں اور کسی نے ان کو نہیں دیکھا تو تم مت گھبراؤ آسمان پر ایک زندہ خدا
موجود ہے جو تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے وہ تمہیں نیکیوں کی جزا دے گا اور تمہارا چھوٹے سے
چھوٹا کام بھی اس کے سامنے اسی طرح آجائے گا جس طرح کوئی بڑے سے بڑا کام آتا ہے.غرض یہ آیت ایسی ہے جو انسانی زندگی کی کایا پلٹنے والی اور لوگوں کے قلوب میں ایک نئی
860
Page 869
امنگ، نئی روح اور نئی بیداری پیدا کرنے والی ہے.جزائے خیر وشر کے متعلق یہ ایک ایسا عظیم الشان اصل ہے کہ اگر اس کو پوری طرح سمجھ لیا
جائے تو صحیح نیکی پیدا ہوتی ہے اور بدی سے بچنے کا صحیح جذ بہ انسانی قلب میں پیدا ہو جاتا ہے.ابوسعید خدری کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا
يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرِّشَر ايره - تو میں نے رسول کریم علیم سے عرض کیا کہ
یارسول اللہ ! کیا میں اپنے ہر عمل کا نتیجہ دیکھوں گا؟ آپ نے فرمایا: ہاں.قُلْتُ تِلْكَ الْكِبَارُ
الكبار.میں نے کہا بڑے بڑے عمل بھی نظر آئیں گے؟ قالَ نَعَمُ.فرمایا: ہاں.قُلْتُ تِلْكَ
الصَّغَارُ الصَّغَارُ.میں نے کہا چھوٹے چھوٹے عمل بھی نظر آئیں گے؟ قَالَ نَعَمُ.آپ نے
فرمایا: ہاں.قُلتُ وانکلی اُتنی.میں نے کہا میری ماں مجھ کو روئے پھر تو میں مرا.قال ابشر
يَا أَبَا سَعِيدِ فَإِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ آمَقَالِهَا يَعْنِى إِلى سَبْحِ مِائَةِ ضِعْفٍ وَيَضْعَفُ اللَّهُ لِمَنْ
یا.آپ نے فرمایا اے ابوسعید! یہ آیت گھبراہٹ پیدا کرنے والی نہیں.یہ تو نیکی اور بدی
کی جزا کے متعلق اللہ تعالیٰ کے قانون کو بیان کرتی ہے.کافر بے شک گھبرا سکتا ہے لیکن
مومن کے لئے گھبرانے کی کوئی وجہ نہیں.کیونکہ خدا تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ہر نیکی کا دس
گنے اجر ملے گا.پس یہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ جو شخص نیکی کا ایک ذرہ بھی کرے گا وہ اسے دیکھے
گا.اس میں خیر دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ جس شخص کی ایک نیکی ہوگی اسے دس گنے بڑا کر کے
دکھایا جائے گا.یعنی جو شخص کوئی ایک نیکی بجالائے گا خدا تعالیٰ کے حضور اس کی دس نیکیاں
لکھی
جائیں گی اور پھر ان دس نیکیوں کو سات گنا کیا جائے گا.گویا ایک نیکی کا اجرستر گنے تک پہنچا
دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا اس سے بھی زیادہ بدلہ دے گا.وَالسَّيِّئَةُ بِمِثْلِهَا
اَوْ يَغْفِرُ الله لیکن اگر کسی نے کوئی بدی کی ہوگی تو اس کا بدلہ اسے اتنا ہی ملے گا جتنا اس نے اس
سے قصور سرزد ہوا ہوگا یا اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا.یعنی نیکی کے متعلق اللہ تعالیٰ کا جو قاعدہ
861
Page 870
ہے وہ بدی کے متعلق نہیں.پس مومن کے لئے گھبراہٹ کا کوئی مقام نہیں ہاں اگر کافر
گھبرائے تو وہ اس کا سزاوار ہے.پھر آپ نے فرمایا وَلَنْ يَنْجُوَ أَحَدٌ مِنْكُمْ بِعَمَلِهِ تم میں
سے کوئی شخص ایسا نہیں جو اپنے عمل کے زور سے نجات حاصل کر سکے.نجات کا موجب عمل
نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے.قُلْتُ وَلَا اَنْتَ يَا رَسُولَ اللہ.میں نے کہا یا رسول اللہ
کیا آپ بھی اپنے عمل سے نجات نہیں پائیں گے؟ قَالَ وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَعَمَّدَنِي اللهُ مِنْهُ
برحمة.آپ نے فرمایا نہیں میں بھی اپنے عمل سے نجات نہیں پاسکتا.میری مغفرت بھی اسی
صورت میں ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے مجھے ڈھانپ لے.درحقیقت اگر ہم غور
کریں تو بات وہی ہے جو غالب نے کہی:
جان دی ، دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا
اگر نبی نیکی کرتا ہے تو وہ بھی خدا تعالیٰ کی دی ہوئی طاقتوں سے ہی کرتا ہے.پس منطقی طور
پر اگر دیکھا جائے تو نبی کے ہاتھ میں بھی سوائے فضل کے اور کچھ نہیں ہوتا.کیونکہ اگر اس نے
نماز پڑھی ہے یا روزہ رکھا ہے یا حج کیا ہے یا صدقہ وخیرات میں حصہ لیا ہے یا اور نیکیاں کی
ہیں تو وہ سب کی سب خدا تعالیٰ کی عطا کردہ طاقتوں سے کی ہیں.اس لئے خالص منطقی نظریہ
سے اگر دیکھا جائے تو نبی کی نجات بھی خدا تعالیٰ کے فضل کے بغیر نہیں ہو سکتی.بے شک عملی
نظریہ میں ایک شخص نیک ہوتا ہے اور ایک بد لیکن منطقی نظریہ کے ماتحت کوئی بڑے سے بڑا
نیک بھی محض اعمال کی بنا پر نجات کا مستحق نہیں سمجھا جا سکتا کیونکہ اس نے جو کچھ کیا اللہ تعالیٰ کی
طاقتوں سے کام لے کر کیا ہے.اس حدیث میں رسول کریم ملا لیا لیلی نے جو کچھ فرمایا ہے خالص
منطقی نظریہ کے ماتحت فرمایا ہے، عملی نظریہ کے ماتحت نہیں.(ماخوذ از تفسير كبير زير سورة الزلزال )
862
Page 871
(XXXXXX
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
الْهُكُمُ التَّكَاثُرُة
حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَة
كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ
ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ
كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ
لَتَرَوُنَ الْجَحِيمَة
ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ
ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَيذٍ عَنِ النَّعِيمِن
سورة التكاثر
1 - (میں) اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا
( اور ) بار بار رحم کرنے والا ہے ( پڑھتا ہوں )
2 تم کو ایک دوسرے سے بڑھنے کی خواہش نے
غفلت میں ڈال دیا ( اور تم اسی طرح غافل رہو گے )
3.یہاں تک کہ تم مقبروں میں جا پہنچو گے.4.( خوب یاد رکھو کہ ) تم لوگ عنقریب ( قرآن
کریم کی بیان کردہ حقیقت کو ) جان لو گے.-5.پھر ( ہم کہتے ہیں کہ تمہاری حالت اس طرح
نہیں جس طرح تم سمجھتے ہو اور ) عنقریب تم کو معلوم
ہو جائے گا ( کہ تمہاری اندرونی حالت حقیقیہ وہی
ہے جو قرآن کریم نے بیان کی ہے )
6.اصل حقیقت تمہارے خیالات کے مطابق )
ہر گز نہیں ( ہے ).کاش تم اصل حقیقت علم یقین کی
مدد سے جان سکتے.7.( تب تم کو معلوم ہو جاتا کہ ) تم ضرور جہنم کو
( اسی دنیا میں ) دیکھو گے.8.اور اس کے بعد تم اسے یقین کی آنکھ سے
(آخرت میں ) بھی دیکھ لو گے.9.پھر ( یہ بھی یاد رکھو کہ) تم سے اس دن ( ہر بڑی )
نعمت کے متعلق سوال کیا جائے گا ( کہ تم نے اس کا شکر
ادا کیا ہے یا نہیں کیا)
863
Page 872
حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں:
دنیا کی کثرت حرص و ہوا نے تمہیں آخرت کی تلاش سے روک رکھا یہاں تک کہ تم
قبروں میں جا پڑے.دنیا سے دل مت لگاؤ تم عنقریب جان لو گے کہ دنیا سے دل لگانا اچھا
نہیں.پھر میں کہتا ہوں کہ عنقریب تم جان لو گے کہ دنیا سے دل لگانا اچھا نہیں.اگر تمہیں یقینی
علم حاصل ہو تو تم دوزخ کو اسی دنیا میں دیکھ لو گے.پھر برزخ کے عالم میں یقین کی آنکھوں کے
ساتھ دیکھو گے.پھر عالم حشر اجساد میں پورے مواخذہ میں آجاؤ گے اور وہ عذاب تم پر کامل طور
پر وارد ہو جائے گا اور صرف قال سے نہیں بلکہ حال سے تمہیں دوزخ کا علم حاصل ہو جائے گا.ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا ہے کہ اسی جہان میں بدکاروں کے لئے جہنمی
زندگی پوشیدہ طور پر ہوتی ہے اور اگر غور کریں تو اپنی دوزخ کو اسی دنیا میں دیکھ لیں گے.اور
اس جگہ اللہ تعالیٰ نے علم کو تین درجوں پر منقسم کیا ہے.یعنی علم الیقین ، عین الیقین حق الیقین.اور عام کے سمجھنے کیلئے ان تینوں علموں کی یہ مثالیں ہیں کہ اگر مثلاً ایک شخص دُور سے کسی جگہ
بہت سادھو آں دیکھے اور دھوئیں سے ذہن منتقل ہو کر آگ کی طرف چلا جائے اور آگ کے
وجود کو یقین کرے اور اس خیال سے کہ دھوئیں اور آگ میں ایک تعلق لا ینفک اور ملازمت
تامہ ہے.جہاں دھواں ہو گا ضرور ہے کہ آگ بھی ہو.پس اس علم کا نام علم الیقین ہے.اور
پھر جب آگ کے شعلے دیکھ لے تو اس کا نام عین الیقین ہے.اور جب اس آگ میں آپ ہی
داخل ہوجائے تو اس علم کا نام حق الیقین ہے.اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جہنم کے وجود کا علم
الیقین تو اسی دنیا میں ہو سکتا ہے.پھر عالم برزخ میں عین الیقین حاصل ہوگا اور عائم حشر اجساد
میں وہی علم حق الیقین کے کامل مرتبہ تک پہنچے گا.( اسلامی اصول کی فلاسفی ، روحانی خزائن جلد 10 صفحه 402)
864
Page 873
جاننا چاہئے کہ قرآن شریف نے علم تین قسم پر قرار دیا ہے.(1) علم الیقین،
(2) عین الیقین، (3) حق الیقین....علم الیقین وہ ہے کہ شئے مقصود کا کسی واسطہ کے ذریعہ سے ، نہ بلاواسطہ پتہ لگایا
جاوے.جیسا کہ ہم دھوئیں سے آگ کے وجود پر استدلال کرتے ہیں پر آگ کو دیکھا نہیں مگر
دھوئیں کو دیکھا ہے کہ جس سے ہمیں آگ کے وجود پر یقین آیا.سو یہ علم الیقین ہے.اور اگر ہم
نے آگ کو ہی دیکھ لیا ہے تو یہ بموجب بیان قرآن شریف یعنی سورہ الهَكُمُ التَّكَاثُرُ کے علم
کے مراتب میں سے عین الیقین کے نام سے موسوم ہے.اور اگر ہم اس آگ میں داخل بھی ہو
گئے ہیں تو اس علم کے مرتبہ کا نام قرآن شریف کے بیان کی رُو سے حق الیقین ہے.اسلامی اصول کی فلاسفی ، روحانی خزائن جلد 10 صفحه 431)
ایمان اس اقرار لسانی و تصدیق قلبی سے مراد ہے جو تبلیغ و پیغام کسی نبی کی نسبت محض
تقویٰ اور دور اندیشی کے لحاظ سے صرف نیک ظئی کی بنیاد پر یعنی بعض وجوہ کو معتبر سمجھ کر اور اس
طرف غلبہ اور رجحان پا کر بغیر انتظار کامل اور قطعی اور واشگاف ثبوت کے دلی انشراح سے
قبولیت و تسلیم ظاہر کی جائے.لیکن جب ایک خبر کی صحت پر وجوہ کاملہ قیاسیہ اور دلائل کافیہ عقلیہ مل جائیں تو اس بات کا
نام ایقان ہے جس کو دوسرے لفظوں میں علم الیقین بھی کہتے ہیں.اور جب خدائے تعالیٰ خود اپنے خاص جذبہ اور موہبت سے خارق عادت کے طور پر انوار
طور پر
ہدایت کھولے اور اپنے آلاء ونعماء سے آشنا کرے اور کد ٹی اور علم عطا فرمادے اور
ساتھ اس کے ابواب کشف اور الہام بھی منکشف کر کے عجائبات الوہیت کا سیر کرا دے اور
اپنے محبوبانہ حسن و جمال پر اطلاع بخشے تو اس مرتبہ کا نام عرفان ہے.جس کو دوسرے لفظوں میں
عین الیقین اور ہدایت اور بصیرت کے نام سے بھی موسوم کیا گیا ہے.اور جب ان تمام مراتب کی شدت اثر سے عارف کے دل میں ایک ایسی کیفیت حالی عشق
اور محبت کے باز نہ تعالیٰ پیدا ہو جائے کہ تمام وجود عارف کا اس کی لذت سے بھر جائے اور
865
Page 874
آسمانی انوار اس کے دل پر بکلی احاطہ کر کے ہر یک ظلمت و قبض و تنگی کو درمیان سے اٹھا دیں
یہاں تک کہ بوجہ کمال رابطه عشق و محبت و باعث انتہائی جوش صدق وصفا کی بلا اور مصیبت بھی
محسوس اللہ ت و مدرک الحلاوت ہو تو اس درجہ کا نام اطمینان ہے.جس کو دوسرے لفظوں
میں حق الیقین اور فلاح اور نجات سے بھی تعبیر کرتے ہیں.مگر یہ سب مراتب ایمانی مرتبہ کے بعد ملتے ہیں اور اس پر مترتب ہوتے ہیں.جوشخص
اپنے ایمان میں قوی ہوتا ہے وہ رفتہ رفتہ ان سب مراتب کو پالیتا ہے.لیکن جو شخص ایمانی
طریق کو اختیار نہیں کرتا اور ہر یک صداقت کے قبول کرنے سے اول قطعی اور یقینی اور نہایت
واشگاف ثبوت مانگتا ہے اس کی طبیعت کو اس راہ سے کچھ مناسبت نہیں اور وہ اس لائق ہرگز
نہیں ہو سکتا کہ اس قادر غنی بے نیاز کے فیوض حاصل کرے.سرمه چشم آریه ، روحانی خزائن جلد 2 صفحہ 73 79)
وہ لوگ بڑی غلطی پر ہیں جو ایک ہی دن میں حق الیقین کے درجے پر پہنچنا چاہتے ہیں.یا درکھو کہ ایک ظن ہوتا ہے اور ایک یقین.ظن صرف خیالی بات ہوتی ہے.اس کی صحت اور
سچائی پر کوئی حکم نہیں ہوتا بلکہ اس میں احتمال کذب کا ہوتا ہے.لیکن یقین میں ایک سچائی کی
روشنی ہوتی ہے.یہ سچ ہے کہ یقین کے بھی مدارج ہیں.ایک علم الیقین ہوتا ہے.پھر عین
الیقین اور تیسرا حق الیقین.جیسے ڈور سے کوئی آدمی دھواں دیکھتا ہے تو وہ آگ کا یقین کرتا ہے
اور یہ علم الیقین ہے.اور جب جا کر دیکھتا ہے تو وہ عین الیقین ہے.اور جب ہاتھ ڈال کر دیکھتا
یہ
ہے کہ وہ جلاتی ہے تو وہ حق الیقین ہے.الحکم جلد 6 نمبر 24 مورخہ 10/ دسمبر 1902، صفحہ 2)
حضرت خلیفہ المسیح الاول رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں :
ضرورتیں تو بے شک انسان کو بہت لگی ہوئی ہیں.خواہ کتنے ہی امور کیوں نہ ہوں اور
خواہ کیسی ہی حاجتیں کیوں نہ ہوں.ان تمام کاموں میں انسان تکالر کو چاہتا ہے.اکثر اوقات
866
Page 875
انسان چاہتا ہے کہ عیش و عشرت کے ایسے ایسے سامان میسر آجاویں.ایسا مکان ہو.ایسا
لباس ہو.اور یہ سب خواہشات انسان کے شامل حال ہیں.پھر ان میں غلطی کیا ہے.خدا
تعالیٰ نے بھی ایک دعا سکھاتی ہے ربِّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً (البقرہ 202) اس دعا میں
اللہ کریم سے اسی دنیا میں حسنہ مانگی گئی ہے.مگر یاد رکھو غلطی صرف یہ ہے کہ ناجائز طریقوں سے
یہ خواہشات پوری کرنے کی کوشش کی جاوے.اور ان دھندوں میں پھنس کر اپنے مولی سے
انسان غافل ہو جاوے.اللہ جل شانہ سے غفلت بہت بُری بلا ہے.حتی زُرتُمُ الْمَقَابِرَ صحیحین میں روایت ہے کہ ابن آدم بوڑھا ہو جاتا ہے.اور دو
چیزیں اس کی جوان رہ جاتی ہیں.ایک ان میں سے حرص مال ہے.ابوھریرہ سے یہ مروی
ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ التکاثر پڑھی اور پھر فرمایا.بندہ کہتا ہے کہ یہ میرا
مال ہے.یہ میرا مال ہے.حالانکہ اس کا مال تو صرف اتنا ہی ہے جو کھالیا.وہ تو فنا کر دیا.اور
جو پہن لیا اس کو پرانا کر دیا.اور جو خدا کی راہ میں دے دیا اس کو آگے کے لئے جمع کیا.ان
تین قسموں کے سوا جو کچھ اور مال ہے وہ تو لوگوں کا ہے.(ماخوذ از حقائق الفرقان )
( ضمیمه اخبار بدر قادیان 19 ستمبر 1912ء)
حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:
م یہ سورۃ جمہور کے نزدیک ملی ہے.رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم نے سورۃ تکاثر کو ہزار
آیات کے برابر بتایا ہے.حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا جو شخص روزانہ رات کو ہزار آیات پڑھ لیا کرے وہ اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں ملے گا
کہ خدا اُسے دیکھ کر خوش ہوگا.صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ طاقت کس انسان کو حاصل ہو
سکتی ہے کہ وہ ہزار آیات روزانہ پڑھا کرے.اس پر آپ نے سورۃ تکاثر کی تلاوت شروع کر
دی یہاں تک کہ آپ اس کے آخر تک پہنچ گئے.پھر آپ نے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم
ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ یہ سورۃ ہزار آیات کے برابر ہے.867
Page 876
اس جگہ ہزار آیات سے قرآن کریم کا چھٹا حصہ مراد نہیں ( کیونکہ سارے قرآن کی
قریبا چھ ہزار آیات ہیں) بلکہ مطلب یہ ہے کہ جو غرض قرآن ہے وہ اِس سورۃ میں بیان کر دی
ہے.کیونکہ عربی زبان میں ہزار سے صرف ہزار کا عدد مراد نہیں ہوتا بلکہ ان گنت اور
بے انتہا چیز کے لئے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے.اور ان گنت اور بے انتہا فائدہ انسان اسی
وقت اٹھا سکتا ہے جب وہ اس غرض کو سمجھ جائے جس کے ماتحت اللہ تعالیٰ نے سلسلہ نبوت
قائم کیا ہے اور جس کو پورا کرنے کے لئے آدم سے لے کر وہ اپنے مامورین دنیا کی اصلاح
کے لئے بھیجتا رہا ہے.پس رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ یہ سورۃ ہزار آیات کے برابر ہے اس کا مفہوم
یہ ہے کہ اگر تم اس سورۃ پر غور کرو اور اس کے مطالب کو ہمیشہ اپنے مدنظر رکھو تو تمہارے متعلق
یہ کہا جا سکے گا کہ تم نے اس سورۃ سے وہ فائدہ اُٹھا لیا جو سارے نبیوں کی بعثت کی اصل غرض
ہے.نبیوں کی بعثت کی غرض یہ ہوتی ہے کہ دنیا کی محبت لوگوں کے دلوں سے نکال دیں اور اللہ
تعالی کا عشق اُن میں پیدا کریں.پس جب کوئی شخص اس سورۃ پر غور کرے گا اور حالتِ سیئہ
سے کوٹ کر حالت طیبہ کی طرف آئے گا تو لازما وہ اس مقصد کو حاصل کر لے گا جس کے لئے
قرآن کریم نازل ہوا اور جس کو پورا کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے ابتدائے عالم سے سلسلہ
نبوت قائم فرمایا ہے.حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی کتابوں اور تقریروں
میں اس بات پر بڑا زور دیا ہے کہ انبیاء کی بعثت کی اصل غرض یہ ہوتی ہے کہ دنیا کی محبت سرد
کر کے خدا تعالیٰ کی محبت لوگوں کے قلوب میں پیدا کریں.پس سورۃ تکاثر نبوت کی اصل غرض
بیان کرنے والی سورۃ ہے اور جو شخص اس سورۃ کے مطالب کو اپنے مدنظر رکھتا ہے وہ اپنی
حالت کو نبیوں کی حالت کے مشابہ بنالیتا ہے.جب کوئی چیز انسان کی توجہ کو ایک طرف سے ہٹا کر دوسری طرف پھیر دے تو عربی
زبان میں اس کے لئے انھی کا لفظ استعمال ہوتا ہے.التکاثُر کثرت سے نکلا ہے اور اس کے
868
Page 877
معنے کثرت میں مقابلہ کرنے کے ہوتے ہیں.مفردات میں لکھا ہے الْهُكُمْ آئی شَغَلَكُمْ
التَّبَارِى فِي كَثْرَةِ الْمَالِ وَالْعِزّ - تکاثر کے معنے ہوتے ہیں ایک دوسرے کا مقابلہ مال اور
عزت کی کثرت میں کرنا.یعنی یہ کہنا کہ ہمارا مال زیادہ ہے یا ہماری عزت زیادہ ہے.تم
ہمارے مقابلہ میں حیثیت ہی کیا رکھتے ہو.پس آلهُكُمُ التَّكَاثُرُ کے معنے یہ ہوئے کہ تم کو
ایک دوسرے سے مال، عزت اور تعداد میں زیادہ ہونے کے فخر نے غافل کر دیا ہے یا بعض
دوسری چیزوں سے تمہاری توجہ ہٹا کر اپنی طرف پھیر لیا ہے.محاورہ زبان میں ہمیشہ انھی کے بعد عن آتا ہے یعنی الْهَادُ عَنْ كَذَا.اسی طرح تکاثر
کے بعد فی آتا ہے یعنی جس چیز کے بارہ میں فخر ہے اس سے پہلے فی آتا ہے اور جس چیز سے
کوئی چیز غافل کر دے اس سے پہلے عج آتا ہے.مگر قرآن کریم نے دونوں صلوں کو چھوڑ دیا
ہے.یعنی اس نے نہ تو یہ کہا ہے کہ تم کو پکا شر نے کسی چیز سے غافل کر دیا ہے اور نہ یہ کہا ہے کہ
تمہیں اپنی کسی چیز کی کثرت سے مغرور بنادیا ہے.درحقیقت دونوں صلوں کو چھوڑ دینے سے
ایک بہت بڑا مضمون بیان کیا گیا ہے....اگر اس چیز کا بھی ذکر کر دیا جاتا جس سے تکاثر نے
ان کو غافل کر دیا تھا تو مضمون محدود ہو جاتا اور اس اجمال میں جو فصاحت پائی جاتی ہے وہ جاتی
رہتی کیونکہ تکا ترکسی ایک نیک بات سے نہیں بلکہ ہر نیک بات سے انسان کو غافل کر دیتا ہے.تکاثر کے معنے ہوتے ہیں ذاتیات کا غلبہ.آخر دنیا میں کیوں ایک انسان دوسرے پر
فخر کرتا ہے.اسی لئے کہ بجائے اللہ تعالیٰ کا فضل دیکھنے کے وہ اپنی ذات کی بڑائی دیکھنے لگ
جاتا ہے.وہ اس بات کو بھول جاتا ہے کہ اگر اس میں کوئی خوبی پائی جاتی ہے تو وہ خدا تعالیٰ کی
عطا کردہ ہے.اگر اس میں کوئی کمال پایا جاتا ہے تو وہ خدا تعالیٰ کا عطیہ ہے.اس کی نگاہ ان
تمام باتوں کو نظر انداز کر کے صرف ذاتی بڑائی کو اپنے سامنے رکھ لیتی ہے اور وہ خیال کرتا ہے
کہ اس نے جو کچھ حاصل کیا ہے اپنے زورِ بازو سے حاصل کیا ہے.پس دوسروں پر فخر کرنے
کا سب سے پہلا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کے سامنے صرف اس کی ذاتی بڑائی رہ جاتی ہے
869
Page 878
خدا تعالیٰ کا فضل جو تمام ترقیات کا اصل باعث ہوتا ہے اسے بھول جاتا ہے.احادیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بڑائی بیان کی
اور پھر فرمایا میں کوئی فخر نہیں کرتا کیونکہ مجھے یہ خوبی محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے حاصل ہوئی
ہے.اس سے ظاہر ہے کہ مومن باوجود بڑائی حاصل ہونے کے تفاخر سے کام نہیں لیتا.کیونکہ
وہ سمجھتا ہے کہ جو چیز میرے لئے موجب فخر ہے وہ مجھے خود بخود حاصل نہیں ہوئی بلکہ میرے اندر
اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے.لیکن غیر مومن ایسا نہیں کرتا.اس لئے جب کسی انسان کے اندر
تکاثر پیدا ہوگا اور وہ اپنی کثرت پر فخر کرے گا یا اپنی عزت پر فخر کرے گا یا اپنے مال پر فخر کرے گا یا
اپنی طاقت پر فخر کرے گا تو لازمی طور پر خدا تعالیٰ کا وجود اس کی نظر سے اوجھل ہو جائے گا اور وہ
سمجھے گا کہ یہ کام میں نے کیا ہے.پس تکاثر کی وجہ سے ایک تو خدا تعالیٰ کے فضل انسانی نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں.پھر اس کے نتیجہ میں خدا تعالیٰ کی ذات بھی اوجھل ہو جاتی ہے.جب کوئی شخص اپنی ذات کو دنیا میں بڑا دیکھتا ہے تو اس کا سوائے اس کی اور کوئی مفہوم
نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ اس کے نگاہ سے اوجھل ہو چکا ہے.گویا تکاثر کے نتیجہ میں اول موجبات
فخر یعنی صفات الہیہ اس کی نظر سے اوجھل ہوتی ہیں اور پھر رفتہ رفتہ خدا تعالیٰ کی ذات بھی اس کی
نظر سے اوجھل ہو جاتی ہے.پس آلهُكُمُ التَّكَاثُرُ کے معنے یہ ہوئے کہ الْهُكُمُ التَّكَاثُرُ عَنْ
صِفَاتِ اللهِ و عَنِ اللہ تمہیں تکاثر نے اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کی ذات دونوں سے غافل
کر دیا ہے.پھر دنیا میں اللہ تعالیٰ کے جتنے فضل نازل ہوتے ہیں سب ملائکہ کے ذریعہ نازل ہوتے
ہیں.لیکن جب کوئی شخص اپنی ذات پر فخر کرتا ہے تو نہ صرف اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کی
ذات کو بھول جاتا ہے بلکہ وہ اس بات کو بھی فراموش کر دیتا ہے کہ میری عزت یا دولت یا
شہرت کے حصول میں محض میری ذاتی کوششوں کا دخل نہیں بلکہ ان ملائکہ کا بھی دخل ہے جو
870
Page 879
اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر قسم کی کامیابی کے سامان مہیا کرتے ہیں.پھر جب بھی کسی کو بڑائی حاصل ہوتی ہے ہمیشہ اضافی طور پر ہوتی ہے.غیر اضافی طور پر
ہمیں دنیا میں کوئی شخص بڑا نظر نہیں آتا.پس جب بھی کوئی فخر کرتا ہے وہ اس حقیقت کو نظر انداز کر دیتا ہے کہ اس سے پہلے بھی
دنیا میں بہت لوگ گزر چکے ہیں اور وہ اپنے اپنے زمانوں میں بڑی شہرت کے مالک رہے
ہیں میرے لئے فخر کا کونسا مقام ہے.پس تکاثر سے کام لینے والا صرف خدا تعالیٰ کی صفات کو
نظر انداز نہیں کرتا ، اس کی ذات کو نظر انداز نہیں کرتا ، اس کے ملائکہ کو نظر انداز نہیں کرتا، بلکہ
دنیاکے سابق علوم اور سابق ایجادات سے بھی انکار کر دیتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کے باپ
دادا تو محض جاہل تھے کمال صرف اسی کو حاصل ہوا ہے.پس تکاثر کا ایک نتیجہ واقعات کے
انکار کی صورت میں رونما ہوتا ہے.پھر اس کے نتیجہ میں تکبر بھی پیدا ہوتا ہے اور غرباء پر ظلم شرو
ع ہو جاتا ہے.بجائے اس کے کہ انسان کا ذہن اس طرف جائے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس
لئے مال دیا ہے کہ میں غریبوں کی خدمت کروں اس کا ذہن اس طرف چلا جاتا ہے کہ میں بڑا
ہوں.میرا کام یہ ہے کہ میں دوسروں سے خدمت لوں اور دوسروں کا کام یہ ہے کہ وہ میری
غلامی اختیار کریں.نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ رفتہ رفتہ تمام اخلاق فاضلہ اس کی نظر سے اوجھل ہو جاتے
ہیں.اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو مجمل الفاظ میں بیان کیا اور انھی کے بعد عج کا ذکر
نہیں کیا.یعنی یہ بیان نہیں کیا کہ تمہیں تکاثر نے کس چیز سے غافل کر دیا ہے تا کہ تمام وہ
چیزیں جن سے تکاثر نے غافل کر دیا یا جن سے تکاثر غافل کر سکتا ہے وہ ایک ایک کر کے
انسان کے ذہن میں آجائیں اور وہ اس مضمون سے زیادہ سے زیادہ سبق حاصل کرے.غرض
اس ابہام میں یہی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ جتنی باتوں سے تکاثر
انسان کو غافل کر دیا کرتا ہے وہ سب کی سب باتیں اس آیت میں شامل ہیں اور ہمارا مقصد یہ
ہے کہ تم کسی ایک نیکی سے نہیں بلکہ سب کی سب نیکیوں سے اس روح مفاخرت کی وجہ سے
871
Page 880
محروم ہو گئے ہو.پس عج کے چھوڑ دینے کی وجہ سے اس مضمون کو نہایت وسیع اور شاندار بنا دیا
گیا ہے.(2) دوسرا صلہ فی کا چھوڑا گیا ہے یعنی یہ نہیں فرمایا کہ تم کس چیز میں اپنی بڑائی
بیان کرتے ہو اور بڑائی حاصل کرنا چاہتے ہو.اس ابہام میں بھی یہ فائدہ مدنظر رکھا گیا ہے کہ
کفار جہاں تک دنیوی طاقت کا سوال ہے ہر بات میں مسلمانوں سے زیادہ تھے.وہ اپنی تعداد
پر بھی فخر کرتے تھے.اپنی تجارت پر بھی فخر کرتے تھے.اپنے وسیع تعلقات پر بھی فخر کرتے
تھے.اپنے جمع کردہ اموال کی کثرت پر بھی فخر کرتے تھے.اپنے نو جوانوں کی جنگی مہارت پر بھی
فخر کرتے تھے.اپنی اعلیٰ سواریوں پر بھی فخر کرتے تھے.اپنے مسحور کر دینے والے شعراء پر بھی
فخر کرتے تھے.اپنے گرمادینے والے خطیبوں پر بھی فخر کرتے تھے.اپنے عقل و دانش میں
مشہور بوڑھوں پر بھی فخر کرتے تھے.قومی جذبات سے معمور سینوں والی ماؤں پر بھی فخر کرتے
تھے.قوم کی عزت پر مر مٹنے والے سپاہیوں پر بھی فخر کرتے تھے اور اسی طرح اور بہت سے
امور میں مسلمانوں کو اپنے سے ادنی اور کمزور قرار دے کر ان کی تحقیر کرتے تھے اور ان کے
دعاوی کو غیر معقول اور بے ثبوت و دلیل دعاوی قرار دیتے تھے.قرآن کریم جہاں تک ان
کے ہرامر میں زیادہ ہونے کا سوال ہے ان کے دعویٰ کو ر ڈ نہیں کرتا.وہ مانتا ہے کہ عدد میں،
مال میں، سامانوں میں، جتھا بندی میں تم زیادہ ہو لیکن صرف اتنا کہتا ہے کہ ان چیزوں کی
زیادتی نے تم کو اخلاق فاضلہ اور دین سے محروم کر دیا ہے اور انسان مال اور دولت سے نہیں
جیتا کرتا بلکہ اخلاق و انکسار سے جیتا کرتا ہے.پس یہ زیادتیاں اور بڑھوتیاں تمہارے لئے
مفید نہیں بلکہ مضر ہیں کیونکہ سامان کم ہوتے تو تم اپنی ترقی کے لئے کوشش کرتے.اب
سامانوں کی فراوانی نے تم کو سست اور غافل بنا دیا ہے اور ان اخلاق کے کمانے سے محروم کر دیا
ہے جن کو کمائے بغیر انسان کو پائدار دولت حاصل نہیں ہوا کرتی.اس لئے یہ دولت تم کو نجات
نہ دلائے گی بلکہ تمہاری تباہی کا موجب ہوگی.گرتے ہوئے سوار ایک بچے سے بھی کمزور
872
Page 881
ہوتے ہیں اور بوسیدہ عمارت ایک جھونپڑی سے بھی بے قیمت ہوتی ہے.م اس سورۃ کا جوشان نزول بتایا جاتا ہے اس کے معنے صرف اتنے ہیں کہ بعض واقعات
کے زمانہ میں بھی ایسے ہوئے جن پر یہ سورۃ چسپاں ہوتی ہے ورنہ یہ سورۃ اپنے اندر بہت
رض
صحاب
وسیع مطالب رکھتی ہے.چونکہ اس سورۃ میں ماضی کے الفاظ استعمال کئے گئے ہیں اس لئے بعض لوگوں کے دل
میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس سورۃ میں ماضی کے الفاظ کس حکمت کے ماتحت استعمال کئے
گئے ہیں اور چونکہ انہوں نے زُرتُمُ الْمَقَابِر کے معنے انسان کے مرجانے اور اس کے قبر میں
داخل ہو جانے کے کئے ہیں.اس لئے بعض نے کہا ہے کہ الْهُكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّى زُرتُمُ
الْمَقَابِر تحقق وقوع کے لئے آیا ہے.یعنی تکاثر نے تم کو غافل کر دیا یہاں تک کہ تم مر گئے.یعنی چونکہ یہ بات ضرور ہو کر رہنی ہے اور موت ایسی چیز ہے جس سے کسی انسان کو مفر نہیں اس
لئے اللہ تعالیٰ نے یہاں ماضی کے الفاظ استعمال کئے ہیں.یہ بتانے کے لئے کہ بات ایسی
قطعی اور یقینی ہے کہ ہم اس کے مضارع کا صیغہ استعمال کرنے کی بجائے ماضی کا صیغہ استعمال
کرتے ہیں.مگر میرے نزدیک یہ بات صحیح نہیں.اس لئے کہ تحقیق وقوع کا مسئلہ وہاں چسپاں
ہوتا ہے جہاں وقوعہ لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہو.مثلاً قرآن کریم نے یہ پیشگوئی کی کہ
محمد رسول اللہ سلیم جیتیں گے اور مکہ کو ایک دن فتح کرلیں گے.اب لگہ کا فتح ہونا کفار کی
نظروں سے بالکل پوشیدہ امر تھا اور وہ اس بات کو کبھی تسلیم نہیں کر سکتے تھے کہ
محمد رسول الله علی ایم کی ایک دن اپنے صحابہ سمیت مکہ میں فاتحانہ طور پر داخل ہوں گے اور کفار
ان کے زیر نگین آجائیں گے.پس چونکہ یہ بات کفار کی نگاہ میں بالکل غیر ممکن تھی اس لئے
اللہ تعالیٰ نے اس پر زور دینے کے لئے ماضی کا صیغہ استعمال کر دیا اور بتادیا کہ تم تو اس پیشگوئی
کو نہیں مانتے لیکن ہم اسے ایسا قطعی اور یقینی سمجھتے ہیں جیسے ماضی یقینی ہوتی ہے اور جس کے
وقوع میں کسی کو کوئی شبہ نہیں ہوتا.لیکن زیارت قبور یا قبروں میں داخل ہونا تو ایک ایسی بات
873
Page 882
ہے جس کا کفار بھی انکار نہیں کرتے تھے اور وہ تسلیم کرتے تھے کہ ہر انسان ایک دن لازماً
مرجائے گا.پس اس قاعدہ کا اطلاق یہاں درست نہیں.یہ قاعدہ وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں
مخاطب تو انکار کر رہا ہو اور متکلم کو اپنے کلام پر زور دینا مقصود ہو.میرے نزدیک ان آیات میں مقابر کے لفظ سے مٹی والی قبریں مراد نہیں بلکہ تباہی اور
بر بادی مراد ہے اور اگر ہم یہ معنے کریں تو یہ آیات اپنے مطالب کے لحاظ سے وسیع بھی ہو جاتی
ہیں اور کسی غیر معمولی تاویل کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آلْهُكُمُ التَّكَاثُرُ.تم لوگوں کو تکاثر نے اتنا غافل بنادیا ہے کہ جن
چیزوں سے تکاثر نے تمہیں روکا تھا ان کی طرف تم لوٹ نہیں سکے یہاں تک کہ تم تباہی کے
سرے پر پہنچ گئے اور تمہاری بربادی کا وقت آگیا.پس زُرتُمُ الْمَقَابِرَ سے مقبرہ جسمانی مراد
نہیں بلکہ یہ وہ مقبرہ ہے جس کا محاورہ زبان میں ذکر کرتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ فلاں قوم
تو مرگئی یا فلاں شخص کے متعلق تم کیا پوچھتے ہو وہ تو مر گیا.یعنی اس کے اندر بیداری کی روح
نہیں رہی، اس میں اخلاقی زندگی نہیں رہی، اس میں دینی زندگی نہیں رہی ، اس میں قومی زندگی
نہیں رہی، اس میں سیاسی زندگی نہیں رہی، اس میں عائلی زندگی نہیں رہی.جب کسی قوم یا فرد
کی یہ حالت ہو تو کہتے ہیں کہ اس پر موت طاری ہو گئی.پس یہاں ان ساری چیزوں کی نفی کی گئی
ہے جن سے تکاثر انسان کو محروم کر دیا کرتا ہے.اور کہا گیا ہے کہ تم میں دین بھی نہیں رہا تم میں
دنیا بھی نہیں رہی، تم میں اخلاق بھی نہیں رہے، تم میں علم بھی نہیں رہا.ایسا آدمی کسی ایک موت
کے نیچے نہیں ہزاروں موتوں کے نیچے دبا ہوا ہوتا ہے.پس آلهُكُمُ الشَّعائر کے معنے یہ ہوں گے کہ قومی طور پر تم پر تنزل اور بربادی کا وہ دور آ گیا
ہے کہ جس کے بعد کوئی قوم زندہ نہیں کہلا سکتی.اور گو اس میں مکہ والے مخاطب ہیں مگر اس
ذریعہ سے یہ قانون بھی بیان کر دیا گیا ہے کہ جو قوم تکاثر کے پیچھے پڑتی ہے وہ مقبرہ کو پہنچ جاتی
ہے.یعنی وہ قوم آخر مر جاتی اور دنیا سے ہمیشہ کے لئے نابود ہو جاتی ہے.874
Page 883
جب ایسا زمانہ آتا ہے کہ انبیاء کی جماعتوں کی دنیوی عزت دیکھ کرلوگ واہ واہ کہنے
لگ جاتے ہیں تو یکا شر کا راستہ کھل جاتا ہے اور وہ اس واہ واہ کے اثر کے نیچے اسی راستہ پر چلنے
لگتے ہیں جس راستہ پر پہلی قومیں چلیں اور جو اصل چیز ہوتی ہے اسے بھول جاتے ہیں.اور جب
دین کو بھول جاتے ہیں تو خالص مقصود دنیا رہ جاتی ہے اور وہ بے تحاشا اس کی طرف بڑھنے لگتے
ہیں.آخر اس کے تین نتائج پیدا ہوتے ہیں.اوّل.بنی نوع انسان میں ان کے خلاف ردعمل پیدا ہوتا ہے.اس کی وجہ یہ ہے کہ تکاثر
کے نتیجہ میں تکبر پیدا ہوتا ہے اور تکبر کے نتیجہ میں لوٹ مار اور ظلم پیدا ہوتا ہے.آخر بنی نوع
انسان میں ان کے خلاف جوش پیدا ہوتا ہے اور وہ حکومت کو تباہ کرنے کے لیے کھڑے ہو
جاتے ہیں.دوم.کبھی بنی نوع انسان میں تو ان کے خلاف رد عمل پیدا نہیں ہوتالیکن ان کی اپنی اولادان
کی کمائی کو استعمال کر کے عیاش ہو جاتی ہے اور اس طرح ان میں اندرونی زوال پیدا ہونے
لگتا ہے.باپ دادا کی جائیداد چونکہ مفت ہاتھ میں آجاتی ہے اس لیے عیاشی میں مبتلا ہو کر وہ
سب کچھ برباد کر دیتے ہیں.بڑے بڑے بادشاہ ہوتے ہیں مگر عیاشی میں مبتلا ہونے کی وجہ
سے ان کی یہ حالت ہوتی ہے کہ انہوں نے کنچنیاں رکھی ہوئی ہوتی ہیں.شرابیں پیتے رہتے ہیں
اور حکومت کے کاموں کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتے.نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ برباد ہو جاتے ہیں
اور ان کی حکومت امراء میں تقسیم ہو جاتی ہے.سوم.یا پھر اللہ تعالیٰ سے ہی اس قوم کی نگر ہو جاتی ہے.یعنی کوئی ایسا سبب پیدا ہو جاتا
ہے کہ دنیوی تباہی کے سامان
تو نہیں ہوتے لیکن خدا تعالیٰ کا عذاب نازل ہو کر اس قوم کو
بالکل تباہ کردیتا ہے.غرض جب کوئی قوم تکاثر کے نتیجہ میں زُرتُمُ الْمَقَابِر کے مقام پر پہنچ جائے تو اس میں ان
تین حالتوں میں سے کوئی ایک حالت ضرور پیدا ہو جاتی ہے.یا تو رعایا میں رد عمل پیدا ہوتا ہے
875
Page 884
اور وہ اپنے حاکموں کو توڑ دیتے ہیں.یا اندرونی طور پر حکام میں ایسا تنزل پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ
آپ ہی آپ ٹوٹنے لگ جاتے ہیں.اور یا پھر خدائی غضب نازل ہو کر ان کو تباہ کر دیتا ہے.یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے جس کا جواب دینا ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ سورۃ تو اہل
مکہ کی نسبت ہے اور ان کے پاس کوئی زیادہ مال نہیں تھا پھر وہ تکاثر کے مجرم کس طرح ہو گئے؟
اس کا جواب یہ ہے کہ ہر قوم کی دولت نسبتی ہوتی ہے اگر ان کے مالدار چھوٹے تھے تو ان
کے غریب بھی تو بہت غریب تھے پس تکا فرنسبتی امر ہے.کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے
پاس کروڑوں نہیں اس لئے میں تکاثر کا مجرم نہیں.امریکہ والوں کے لئے تکاثر کے اور معنے
ہیں.انگلستان کے لئے اور.اور ہندوستان کے لئے اور اس میں سے ہندوؤں کے لئے
اور.مسلمانوں کے لئے اور.پھر احمدیوں کے لئے اور.جس قوم پر جو ذمہ واری ہے چھوٹی ہو یا
بڑی، اگر وہ اس ذمہ واری کو ادا کرنے سے قاصر ہے تو پکا شر کی مرتکب ہے بلکہ جب بھی دین یا
دنیا کے کسی اچھے کام کے لئے کسی قربانی کی ضرورت ہے اور کوئی شخص اس وقت اپنے ہاتھ کو
پیچھے کھینچ لیتا ہے گو اس کے پاس ایک ٹکڑا روٹی کا ہی تھا وہ تکا شر کا مرتکب ہے کیونکہ اس نے
ایک چیز اپنے پاس رکھ لینی چاہی جو دوسروں نے قربان کر دی تھی یا جس کی اس کے دین یا اس
کی قوم کو ضرورت تھی.جس قوم میں یہ نقص پیدا ہو جائے اور قربانی میں دریغ کرنے لگے وہ تباہ ہو
جاتی ہے.اسی لئے فرما یا حتی زُرتُمُ الْمَقَابِر یعنی یہ مرض آخر قومی موت کی طرف لے جاتا ہے.اس جگہ یہ سال بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا تکاثر اور تفاخرکی طور پر منوع ہے؟
اس کا جواب یہ ہے کہ اس جگہ اس تکاثر کا ذکر ہے جو انسان کو موت تک پہنچا دیتا ہے.جیسا کہ فرماتا ہے اَلْهُكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِر.اس تکاثر نے تم کو تمام نیک باتوں
سے غافل کر دیا ہے یہاں تک کہ تم موت تک پہنچ گئے ہو.یعنی اگر نیک باتوں پر فخر ہو یا ایسی
باتوں پر فخر ہو جو دوسروں کو نیکی اور تقویٰ کی طرف لانے میں محمد ہوں تو اس قسم کا تفاخر منع نہیں.گویا تفاخر کی دو قسمیں ہیں.ایک تفاخر وہ ہے جو انسان کو مقابر کی طرف لے جاتا ہے.اور
ایک تفاخر وہ ہے جو انسان میں زندگی پیدا کرتا ہے.جو تفاخر انسان کو مقابر کی طرف لے جاتا
876
Page 885
ہے وہ کلی طور پر ممنوع ہے.اور جو تفاخر زندگی پیدا کرتا ہے وہ منع نہیں.چنانچہ رسول کریم علیم کے متعلق آتا ہے کہ آپ نے ایک دفعہ فرمایا انا سيد ولد آدم
وَلَا فَجر مجھے خدا تعالیٰ نے تمام بنی نوع انسان کا سردار بنایا ہے مگر اس کے باوجود میں اس پر فخر
نہیں کرتا.یہ نہیں کہ میں تم کو ذلیل سمجھوں اور اپنے آپ کو تم سے کوئی علیحدہ ہستی قرار دوں.میرا فرض ہے کہ میں سید ولد آدم ہونے کے باوجود تمہاری خدمت کروں اور تمہیں ترقی کے
میدان میں بہت آگے لے جاؤں.اسی طرح فرماتے ہیں تَزَوَّجُوْا وُلُودًا وُدُودًا فَأَنَا مُكَاثِرُ بِكُمُ الْأُمَمَ وَمُفَاخِرُ بِكُمْ
(ابو داؤد) تم شادیاں کرو جننے والی اور محبت کرنے والی عورتوں سے کیونکہ تمہارے ذریعہ سے
میں دوسری قوموں پر فخر کرنے والا ہوں.اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کثرت تعداد کو صرف
جائز ہی نہیں بلکہ پسندیدہ قرار دیتا ہے مگر چونکہ بعض کثرتیں نہایت گندی ہوتی ہیں اس لئے
رسول کریم علیم نے فرمایا کہ میں صرف یہ خواہش نہیں رکھتا کہ تم اپنی تعداد کے لحاظ سے
دوسری قوموں سے بڑھ جاؤ بلکہ میری خواہش یہ بھی ہے کہ باوجود کثیر ہونے کے تم ایسے نیک
اور پاک بنو کہ میں قیامت کے روز دوسری امتوں کے مقابلہ میں تم پر فخر کر سکوں.اس حدیث
میں وُلُود کا لفظ کثرت کی طرف اشارہ کرتا ہے اور وُدُود میں تفاخر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے
کیونکہ رسول کریم عالی محض کثرت پر نہیں بلکہ اپنی امت کے اعلیٰ اخلاق پر فخر کریں گے اور
اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اگر ماں باپ اپنی اولاد کی اعلیٰ تربیت کریں اور کوشش کریں کہ ان کی
نیکی صرف ان کی ذات تک محدود نہ رہے بلکہ اس کا اثر نسلاً بعد نسل ان کی اولاد میں بھی منتقل ہوتا
چلا جائے تو وہ ایسی اعلیٰ درجہ کی نسلیں پیدا کر سکتے ہیں جو اسلام اور رسول کریم علیم کے لئے
باعث فخر ہوں.افسوس کہ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی طرف توجہ کرتے ہیں.ان
میں ذاتی طور پر تقویٰ بھی ہوتا ہے، روحانیت بھی ہوتی ہے، اعلیٰ اخلاق بھی ہوتے ہیں، رافت
877
Page 886
اور شفقت کے جذبات بھی ہوتے ہیں، حلم بھی موجود ہوتا ہے،حصول علم کی بھی پیاس ہوتی ہے،
نیکیوں میں بڑھنے کا مادہ بھی ہوتا ہے مگر اس بات کی طرف انہیں کبھی توجہ پیدا نہیں ہوتی کہ اپنی
اولاد میں بھی وہ یہ اوصاف پیدا کرنے کی کوشش کریں.بے شک ورثہ کے ذریعہ بھی ماں
باپ کے بعض خصائص اولاد میں منتقل ہو جاتے ہیں مگر اعلیٰ نسل کا بہت بڑا تعلق اعلیٰ تربیت سے
ہوتا ہے اور مومن کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اس پہلو میں کبھی غفلت سے کام نہ لے.اگر ہر شخص خواہ
وہ چھوٹا ہو یا بڑا اپنی اولاد کی نیک تربیت میں مشغول ہو جائے تو کوشش کرے کہ اس کی اولاد
اس سے بڑھ کر اسلام کی فدائی ثابت ہو تو مسلمانوں میں کبھی تنزل پیدا نہ ہو.بڑی وجہ قومی
انحطاط کی یہی ہوتی ہے کہ اولاد کی تربیت کی طرف توجہ نہیں کی جاتی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کثرت
محض بیکار بن کر رہ جاتی ہے اور قوم کا رعب بالکل مٹ جاتا ہے.پس اصل چیز جس کی طرف
توجہ کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہماری آئندہ نسلیں نیکی اور تقوی کے میدان میں ہم سے
بھی تیز تر ہوں کیونکہ یہی وہ چیز ہے جس پر رسول کریم ملی فخر کر سکتے ہیں.محض کثرت ایسی چیز
نہیں جو کسی کو مطمئن کرنے کے لئے کافی ہو.پھر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ مومنوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتا ہے فَاسْتَبِقُوا
الخيرات (البقرة (149) اے مومنو! تم نیکیوں میں بڑھنے کی کوشش کرو.اشتیاق کے معنی
صرف خود بڑھنے کے نہیں ہوتے بلکہ دوسروں کو بھی اپنے ساتھ لے کر آگے بڑھنے کے ہوتے
ہیں.پس اس حکم کا صرف اتنا مفہوم نہیں کہ تمہیں ذاتی طور پر نیکیوں میں ترقی کرنی چاہیے بلکہ
اس کا یہ بھی مفہوم ہے کہ تمہیں دوسرے لوگوں کو بھی اپنے ساتھ اس دوڑ میں شامل کرنا چاہیے اور
شانہ بشانہ چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہیے.اگر کسی قوم میں استباق کی روح پیدا
ہو جائے تو وہ اپنی ترقی کی منازل سالوں اور مہینوں کی بجائے دنوں اور گھنٹوں میں طے کرسکتی
ہے.مثلاً اگر کسی شخص نے قرآن مجید کا ایک پارہ پڑھ لیا ہے تو وہ اس حکم کے مطابق کوشش
کرے گا کہ دوسروں کو بھی وہ پارہ پڑھا دے اور اگر کسی نے ترجمہ پڑھ لیا ہے تو وہ کوشش
878
Page 887
کرے گا کہ دوسروں کو بھی قرآن کریم کا ترجمہ پڑھا دے اور اگر کوئی شخص قرآن کریم کے
معارف سے آگاہ ہو گیا ہے تو وہ کوشش کرے گا کہ میں دوسروں کو بھی قرآن کریم کے
معارف سے آگاہ کر دوں.غرض استباق کی روح اگر کسی قوم میں پیدا ہو جائے تو وہ آن کی آن
میں کہیں کی کہیں جا پہنچتی ہے.اسی طرح فرماتا ہے وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ (فاطر 33)
مومنوں میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو نیکیوں میں دوسروں سے آگے نکل جاتے ہیں.پھر
فرماتا ہے فالسَّابِقاتِ سَبُقًا (النازعات (5) مومنوں کی یہ علامت ہوتی ہے کہ وہ ایک
دوسرے سے نیکیوں میں مقابلہ کرتے ہوئے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں.در حقیقت یہ علامت ان اقوام کی ہے جو اپنے اندر زندگی کی روح رکھتی ہیں.وہ ہمیشہ کوشش
کرتی ہیں کہ دوسروں سے آگے نکل جائیں اور نیکی کے میدان میں کسی کو سبقت نہ لے جانے
دیں.اسی طرح فرماتا ہے سَارِعُوا إلى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ (ال عمران (134) اے لوگو تم
اپنے رب کی مغفرت کی طرف ایک دوسرے سے جلد پہنچنے کی کوشش کرو.یعنی تیزی کے
ساتھ اپنے قدم بڑھاؤ اور خدا تعالیٰ کی مغفرت کو جلد سے جلد حاصل کرنے کی کوشش کرو.یہ
امر ظاہر ہے کہ جولوگ خدا تعالیٰ کی مغفرت کی طرف سرعت سے اپنے قدم بڑھائیں گے ان
میں سے کوئی آگے نکل جائے گا اور کوئی پیچھے رہ جائے گا.کسی شخص کو اس بات پر فخر ہوگا کہ میں
نے دوڑ کر اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا مقام حاصل کر لیا اور کوئی حسرت و افسوس کے ساتھ آہ بھرے گا
کہ میں نے وقت ضائع کر دیا اور خدا تعالیٰ کی مغفرت کو اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے حاصل نہ کر
سکا.بہر حال یہ آیات بتاتی ہیں کہ بعض قسم کے تفاخر اسلام میں ممنوع نہیں.وہ تکاثر جو انسان کو بنی نوع انسان کی خدمت میں مشغول کر دے، جس تکاثر کے نتیجہ میں
انسان کی روحانیت اور اس کا تقویٰ بڑھ جائے ، جس تفاخر کے نتیجہ میں قوم کا معیار بلند ہو جائے
وہ بُرا نہیں بلکہ اچھا ہے.اور ہر سمجھدار انسان کا فرض ہے کہ وہ اس تکاثر میں حصہ لے کیونکہ بغیر
اس کے کوئی قوم زندہ نہیں رہ سکتی.879
Page 888
پس تکاثر اور تفاخر کی ہر صورت ممنوع نہیں بلکہ صرف وہ تفاخر ممنوع ہے جوانسان کو
مقابر کی طرف لے جاتا ہے.یہی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے الْهُكُمُ التَّكَاثُرُ کے بعد زُرْتُمُ
الْمَقَابِر کہا.کیونکہ جسمانی موت تو خود آتی ہے لیکن یہ دینی یا اخلاقی یا قومی ہلاکت انسان خود
بلاتا ہے اور اپنے قدموں چلتا ہوا اپنی قبر میں جا لیٹتا ہے.اگر حَتَّی زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ کی جگہ
حتى متم فرماتا تو یہ مضمون ادا نہ ہو سکتا.حَتَّی زُرتُمُ الْمَقَابِر کہہ کر اللہ تعالیٰ نے مضمون میں
ایک خاص شان اور جدت پیدا کرتے ہوئے بنی نوع انسان کو اس نہایت اہم نکتہ کی طرف توجہ
دلائی ہے کہ قومی تباہی کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ ناجائز تکاثر سے کام لینا شروع کر دیتے
ہیں اور وہ تمام نیک اخلاق جو انسان کی قومی اور مذہبی زندگی کا اصل باعث ہوتے ہیں ان کو
نظر انداز کر دیتے ہیں.نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس روح مفاخرت کی وجہ سے قوم اپنے مقام سے گرتی
چلی جاتی ہے یہاں تک کہ ایک دن ایسا آتا ہے جب موت اس پر پوری طرح سوار ہو جاتی
ہے اور ترقی کی دوڑ میں ایک بے جان جسم سے بڑھ کر اس کی کوئی حقیقت نہیں رہتی.كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ
( خوب یاد رکھو کہ تمہاری حالت ) اس طرح نہیں ( جس طرح تم سمجھتے ہو بلکہ ) تم لوگ
( قرآن کریم کی بیان کردہ حقیقت کو جلد ہی جان لو گے پھر ( ہم کہتے ہیں کہ تمہاری
حالت ) یوں نہیں ( جس طرح تم سمجھتے ہو ) تم عنقریب ہی ( اس بات کو ) جان لو گے.لا ہمیشہ زجر کے لئے استعمال ہوتا ہے اس جگہ بھی اہل مکہ کو خبر دار اور ہوشیار کرنے
کے لئے یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ ان سے خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ
خبر دار تمہاری یہ حالت سخت خطرے والی ہے.ہم نے جو کہا ہے کہ الْهَكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّى
زُرْتُمُ الْمَقَابِر تمہیں تکاثر نے گراتے گراتے اس حالت تک پہنچادیا ہے کہ تم مقبرہ میں جا
پہنچے ہو.ہماری اس بات کی سچائی کو ابھی تم سمجھے نہیں اور تم خیال کرتے ہو کہ یہ محض ایک بڑ
ہے.مگر یاد رکھو تھوڑے ہی دنوں تک تمہیں اچھی طرح پتہ لگ جائے گا کہ ہماری بات بالکل
880
Page 889
سچی ہے اور زندگی کے آثار تم میں موجود نہیں رہے.دیکھو اگر یہاں مقابر سے ظاہری قبریں مراد ہوتیں تو كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ.ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ
تَعْلَمُونَ کے کیا کوئی بھی معنے ہو سکتے تھے؟ کیا ابوجہل ، عتبہ اور شیبہ ی تسلیم نہیں کرتے تھے کہ
ہم نے ایک دن مر جاتا ہے؟ جب وہ بھی تسلیم کرتے تھے کہ انسان فانی ہے اور وہ تھوڑی سی عمر
لے کر اس دنیا میں آیا ہے تو یہ کہنا کس قدر بے معنی ہو جاتا تھا کہ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ تم نے
ضرور مرنا ہے.دیکھو ہم پھر تمہیں بتاتے ہیں کہ تم نے ضرور مرنا ہے.اس صورت میں تو یہ ایک
ہنسی کے قابل بات بن جاتی ہے کہ جس کو ہر فرد تسلیم کرتا ہے اس کے متعلق کہا جارہا ہے کہ
دیکھو تمہیں اس کا عنقریب پتہ لگ جائے گا.میں پھر کہتا ہوں کہ تمہیں اس کا عنقریب پتہ لگ
جائے گا.یہ الفاظ صاف بتارہے ہیں کہ اس جگہ تباہی اور ذلت ورسوائی والی قبر ہی مراد ہے اور یہی وہ
قبریں تھیں جن کا کفار مکہ کو بڑی سختی سے انکار تھا.مٹی کی قبروں کو تو ابوجہل بھی تسلیم کرتا تھا مگر
وہ اس بات کو ماننے کے لئے ہر گز تیار نہیں تھا کہ محمد رسول اللہ صلی بی ایم کے مقابلہ میں میں بار
جاؤں گا.رض
كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ - ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ.میں جو تکرا ر آیا ہے اس کے متعلق
بعض نے کہا ہے کہ یہ تکرار تاکید مضمون کے لیے آیا ہے.رسول کریم علیہ بھی خاص مواقع
پر بات کو بار بار دہراتے تھے.اس صورت میں ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ میں یہ محذوف سمجھا
جائے گا کہ ثُمَّ أَقُولُ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ.حضرت علیؓ کا قول ہے اس جگہ تکرار حصہ نہیں
بلکہ چونکہ واقعہ مکث رہو گا اس لئے دو دفعہ بیان کیا ہے.ان کے نزدیک پہلا تعلمون قبر کے
متعلق ہے اور دوسرا نشر کے متعلق.وہ فرماتے ہیں آلأَوَّلُ فِي الْقُبُورِ وَالثَّانِي فِي النُّشُورِ مگر
میرے نزدیک اس جگہ یا تو تکرار تو کید ہے یا پہلا جملہ دنیا کے متعلق ہے اور دوسرا آخرت کے
متعلق.جیسے فرما يا مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ آغمی (بنی اسرائیل 73) یعنی تمہیں
881
Page 890
دنیا میں بھی اپنی ان حرکات کا انجام معلوم ہو جائے گا اور آخرت میں بھی تم عذاب الہی میں مبتلا
کیے جاؤ گے.كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ لَتَرَوُنَ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ
الْيَقِينِ.(حقیقت تمہارے خیالات کے مطابق ہر گز نہیں ہے ) کاش تم علم یقینی کے ساتھ ( حقیقت
کو) جانتے ( تو تم کو معلوم ہو جاتا کہ ) تم ضرور جہنم کو ( اسی دنیا میں ) دیکھو گے ( بلکہ ) پھر تم
اسے یقین کی آنکھ سے ( آخرت میں) بھی دیکھ لو گے.سابق مضمون کے تسلسل میں اللہ تعالیٰ کفار مکہ سے خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ
ہم پھر کہتے ہیں کہ خبردار ہو جاؤ.کیوں
تمہیں پتہ نہیں لگتا کہ تم ہلاکت اور بربادی کے گڑھے میں
گر چکے ہو.یہ بات تو بالکل قطعی اور یقینی ہے کہ تم مر چکے ہو.زندگی کی کوئی علامت تم میں باقی
نہیں رہی.موت کے سب سامان تمہارے لیے پیدا ہو چکے ہیں.خدا تعالیٰ کو تم بھلا چکے ہو
بنی نوع انسان کے حقوق کو کلیت فراموش کر چکے ہو اور یہی دو چیزیں کسی قوم کی زندگی کی علامت
ہوا کرتی ہیں.قوم زندہ ہوتی ہے اسی طرح کہ خدا اُس قوم کے افراد کے دلوں میں زندہ ہوتا
ہے.جس قوم یا جس فرد کے دل میں اللہ تعالیٰ زندہ ہو وہ انسان زندہ کہلاتا ہے اور یا پھر
بنی نوع انسان کی خدمت کا جذبہ کسی انسان کے دل میں ہو تو وہ انسان زندہ ہوتا ہے.مگر تمہاری
حالت تو یہ ہے کہ نہ تمہیں خدا تعالیٰ کی طاقتوں پر کوئی یقین ہے، نہ بنی نوع انسان کی خدمت کا
کوئی جذبہ تمہارے اندر پایا جاتا ہے.کاش تمہیں علم الیقین ہی ہوتا تب بھی تم اس حقیقت کو
بھانپ لیتے اور سمجھ لیتے کہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ درست ہے.یعنی جانے دو اس بات کو کہ
ہم نے تمہاری ہلاکت کے متعلق پیشگوئی کی ہے اور تم کہتے ہو کہ ہمیں اس پیشگوئی کے پورا
ہونے کا کوئی اعتبار نہیں.مگر دنیا میں ہر فعل کا ایک مادی نتیجہ بھی ہوتا ہے اور جب کوئی شخص
کسی فعل کا ارتکاب کرتا ہے وہ جانتا ہے کہ میرے اس فعل کا کیا نتیجہ نکلے گا تو کیا تم اس نقطہ نگاہ
سے اپنی حالت پر غور نہیں کر سکتے.882
Page 891
لطیفہ مشہور ہے کہ شیخ چلی درخت پر چڑھا تو اسی شاخ کو کاٹنے لگ گیا جس پر وہ بیٹھا ہوا
تھا.نیچے سے کوئی شخص گزرا تو اس نے شیخ چلی سے کہا کہ میاں تم یہ کیا کر رہے ہو کہ اسی
شاخ کو کاٹ رہے ہو جس پر خود بیٹھے ہو تم تو گر جاؤ گے.شیخ چلی نے کہا تو کوئی عالم الغیب
ہے.تجھے کس طرح پتہ لگا کہ میں گر جاؤں گا.جاؤ میں تمہاری بات نہیں مانتا.وہ چلا تو تھوڑی
دیر کے بعد ہی شاخ کے کٹتے ہی شیخ چلی بھی نیچے آ گرا.یہ دیکھ کر وہ اس شخص کے پیچھے بھاگا
اور کہنے لگا معلوم ہوتا ہے تو ولی ہے.کیونکہ جو بات تو نے کہی تھی وہ بالکل سچی نکلی اور میں گر
پڑا.اس نے کہا میں ولی نہیں.میں نے ایک طبعی نتیجہ نکالا تھا کہ چونکہ تم اسی شاخ کو کاٹ
رہے ہو جس پر خود بیٹھے ہو اس لئے تمہارا گرنا یقینی ہے.تو ہر فعل کا ایک طبعی نتیجہ ہوتا ہے جو
بہر حال نکلتا ہے اور عقلمند انسان سمجھتا ہے کہ میں نے جو کچھ کیا ہے اس کا کیا اثر ہو گا.مگر اللہ
تعالیٰ فرماتا ہے تمہاری عقلیں تو اتنی ماری ہوئی ہیں کہ تم ذرا بھی غور سے کام نہیں لیتے.اگر تم
علمی طور پر ہی غور کرتے تو تمہیں یقین آجاتا کہ تم مر رہے ہو اور بلاکت کے سامان تمہارے
لیے چاروں طرف سے جمع ہیں.قومی ہلاکت کے ایک خدائی سامان ہوتے ہیں اور ایک
دنیوی سامان ہوتے ہیں.خدائی سامان تو یہ ہوتے ہیں کہ مثلاً اللہ تعالیٰ کو نہ مانا، اس کے
نبیوں کو نہ مانا، اس کے احکام کی خلاف ورزی کی.اور دنیوی سامان یہ ہوتے ہیں کہ قوم میں
ظلم پایا جائے.غرباء ومساکین کی طرف اسے کوئی توجہ نہ ہو.عیاشی میں اس کے دن رات بسر
ہونے لگیں.یہ دونوں سامان تمہارے لیے جمع ہیں.تم نے خدا تعالیٰ کو بھی ناراض کر لیا ہے
اور بنی نوع انسان سے بھی تمہارا سلوک سخت ناقص ہے اور جب حالت یہ ہے تو تم کیونکر سمجھتے ہو
کہ تم موت سے بچ سکو گے.پس فرماتا ہے كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ.لَتَرَوُنَ الْجَحِيمَ اگر تم میری بات نہیں
مانتے تو نہ مانو.جو کچھ میں کہتا ہوں اسے جھوٹ کہ دو مگر کیا تم نے علمی رنگ میں بھی کبھی اپنے
حالات پر غور نہیں کیا.کاش تمہیں علم الیقین ہی ہوتا تو تم سمجھتے کہ جس قوم میں تعلیم نہ ہو، جس قوم
میں صدقہ و خیرات کی عادت نہ ہو، جس قوم میں انصاف نہ ہو، جس قوم میں انتظام نہ ہو، جس قوم
883
Page 892
میں رافت نہ ہو اور رحمت نہ ہو وہ یقیناً بلاک ہو جاتی ہے.اس میں کسی نبی کے بتانے کی
ضرورت نہیں ہوتی.پس اگر تم میری باتوں کو تسلیم نہ کرتے صرف اپنے اندر علم الیقین پیدا کر
لیتے تب بھی تم دیکھ سکتے تھے کہ جہنم تمہارے سامنے کھڑی ہے.تم دیکھتے کہ ہم قوم کو تعلیم نہیں
دے رہے تم دیکھتے کہ ہم قوم سے انصاف نہیں کر رہے.تم دیکھتے کہ ہم میں دیانت کی روح
موجود نہیں.تم دیکھتے کہ ہم میں امانت کی روح موجود نہیں.تم دیکھتے کہ ہم میں تقویٰ کی روح
موجود نہیں.اگر تم دیکھتے کہ ہم میں عدل و انصاف کی روح موجود نہیں.اسی طرح تم دیکھتے کہ
ہم روپیہ کو صیح طور پر خرچ نہیں کر رہے.ہم اپنے باپ دادوں کی جائیدادوں کو عیاشی میں برباد
کر رہے ہیں.اگر تم ان باتوں پر ذرا بھی غور کرتے تو لتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ تم جہنم کو سامنے کھڑا
پاتے.یعنی تم میری باتوں کو بے شک جھوٹ سمجھ لولیکن اگر تم اپنے حالات پر پوری سنجیدگی کے
ساتھ غور کرتے تو تم دیکھ سکتے تھے کہ جہنم تمہارے سامنے موجود ہے.لتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ کے متعلق بعض نے کہا ہے کہ یہ قسم محذوف کا جواب ہے کیونکہ جیم
دیکھنا کفار کے علم یقین کے ساتھ لازم نہیں ہے.لیکن یہ درست نہیں کیونکہ رؤیت بھی کئی قسم کی
ہوتی ہے.رؤیت عقلی ، رؤیت عینی اور رؤیت مشاہدہ علم الیقین کے بدلہ میں بھی ایک رؤیت
حاصل ہوتی ہے جو رؤیت علمی ہوتی ہے.جب کسی شخص کو بہ دلائل کسی آنے والی مصیبت کا علم
ہو جاتا ہے تو اس علم کے مطابق اس کے قلب کو اس مصیبت کے متعلق تکلیف بھی محسوس ہونے
لگتی ہے.حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی معنے مراد لیے ہیں اور فرمایا ہے کہ اس سورۃ
میں علم کی دو اقسام بیان کی گئی ہیں.علم الیقین اور جو علم اس کے بعد آتا ہے یعنی عین الیقین.یقین
کی ایک تیسری قسم بھی آپ نے بیان کی ہے یعنی حق الیقین جس کا ذکر سورۃ الحاقہ میں ان الفاظ
میں ہے کہ وَإِنَّهُ لَحَق الْيَقِينِ (الحاقة (52) پس اس جگہ رؤیت سے مراد رویت عقلی یا رویت
علمی ہے.884
Page 893
ثُمَّ لتَرَوُهَا عَيْنَ الْيَقِينِ کہ کر فرمایا کہ یہ تو علمی بات تھی مگر میں پھر کہتا ہوں کہ تم ضرور
دیکھ لو گے کہ موت تمہاری آنکھوں کے سامنے کھڑی ہے.ابھی تک تو تمہیں علمی رؤیت بھی
حاصل نہیں لیکن تھوڑے دنوں تک تمہیں علمی رؤیت ہی نہیں بلکہ عینی رؤیت بھی حاصل ہو
جائے گی.یعنی صرف دنیوی احساس ہی تباہی کے قریب پیدا نہ ہوگا بلکہ واقعہ میں پھر بلا نازل
ہو جائے گی اور اسے تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے کیونکہ مجھے خدا نے بتایا ہے کہ تم ضرور تباہ ہو
جاؤ گے.یہ معنے بھی ہو سکتے ہیں کہ تم پہلے دنیا میں اپنی تباہی دیکھو گے اور پھر آخرت میں عذاب الیم کا
شکار بنو گے.ثُمَّ لَتُسْتَلُنَّ يَومَيْل عَنِ النَّعِيمِ
پھر یہ بھی یادرکھو کہ ) تم سے اس دن ( ہر بڑی ) نعمت کے متعلق سوال کیا جائے گا ( کہ
تم نے اس کا شکر ادا کیا یا نہ )
نعيم کا لفظ جو اس آیت میں استعمال ہوا ہے اس کے متعلق عربی سے ناواقف لوگ
خیال کرتے ہیں کہ یہ جمع ہے....عام تراجم میں بھی غلطی سے نعیم کے معنے نعمتوں کے ہی
کئے جاتے ہیں مگر یہ درست نہیں.نعیم کے معنے صرف نعمت کے ہیں نعمتوں کے نہیں.مگر
اس لفظ کی بناوٹ کچھ ایسی ہے کہ لوگ اس سے دھو کہ کھا جاتے ہیں.النعیم سے میرے نزدیک اس جگہ محمد رسول اللہصل تعلیم کا وجود مراد ہے اور اللہ تعالیٰ
فرماتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے، تباہ اور برباد ہو جاؤ گے تو اس وقت میں تم سے پوچھوں گا کہ بتاؤ
محمد رسول اللہ علیم نعمت تھے یا نہیں؟ انہوں نے کب سے تمہیں ہوشیار کرناشروع کیا تھا کہ
بچ جاؤ ، ہلاکت اور تباہی کے گڑھے میں اپنے آپ کومت گراؤ.مگر تم نے ان کی نصیحت پر کام
نہ دھرا اور آخر وہ وقت آ گیا جب تم سچ سچ تباہ ہو گئے تم غور کرو کہ کتنی بڑی نعمت تھی جو ہم نے
تمہاری طرف بھیجی مگر تم نے اس سے کچھ بھی فائدہ نہ اٹھایا.اس نے تمہیں وقت پر ہوشیار کر دیا
885
Page 894
تھا کہ دیکھو تم ایک خطر ناک گڑھے میں گر رہے ہو سنبھل جاؤ اور اپنے آپ کو ہلاکت سے
بچالو.مگر تم پھر بھی نہ بچے اور اپنے آپ کو تباہ کر لیا.یہ بھی ہوسکتا ہے کہ النعیم سے ہر بڑی نعمت مراد ہو.اس صورت میں اس آیت کا یہ مفہوم
ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ایک ایک کر کے اپنی تمام بڑی نعمتیں ان کے سامنے پیش کرے گا اور کہے گا
کہ میں نے تمہیں یہ نعمت بھی دی وہ نعمت بھی دی مگر تم نے میری ساری نعمتوں کو ضائع کر دیا.میں نے تمہیں روپیہ دیا تو تم نے اپنے گھروں میں رکھ لیا اور یہ پسند نہ کیا کہ تم غریبوں پر خرچ کرو
یا صدقہ و خیرات دو.یتامیٰ و مساکین کی خبر گیری کرو.میں نے تمہیں حکومت دی تو تم نے لوگوں
پر ظلم کرنا شروع کر دیا.میں نے تمہیں عزت دی تو تم نے لوگوں کو ذلیل سمجھنا شروع کر دیا.غرض کونسی نعمت تھی جو میں نے تمہیں دی اور تم نے اس کا بُرا استعمال نہ کیا.پس النعیم کے دونوں معنے ہو سکتے ہیں.یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ النعیم سے نعمت کاملہ یعنی
محمد رسول الله لا علم کا وجود مراد ہو.اس صورت میں اس کا یہ مفہوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان سے اپنی
نعمت کا ملہ یعنی محمد رسول اللہ علی ایم
کے متعلق سوال کرے گا کہ تم نے اس کی نصیحتوں سے کیوں
فائدہ نہ اٹھایا.اور یہ معنے بھی ہو سکتے ہیں کہ النعیم سے ہر بڑی نعمت مراد ہو.یعنی مال
و دولت ، عزت و رسوخ اور حکومت جو خدا نے انہیں دی تھی اس کے متعلق ان سے سوال کیا
جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ خدا تعالیٰ کے اتنے بڑے احسانات کے ہوتے ہوئے تم نے
ان نعمتوں سے کیا فائدہ اٹھایا.دنیا میں بھی تباہ شدہ اقوام پر لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ کا ایک وقت آیا کرتا
ہے.جب قومیں تباہ ہوتی ہیں اس وقت کف افسوس ملتی ہوئی ایک دوسرے سے کہا کرتی ہیں
کہ ہمیں فلاں موقع ملا مگر ہم نے ضائع کر دیا.فلاں موقع ملا مگر ہم نے اس سے کچھ فائدہ نہ
اٹھایا.کاش ہم سنبھل جاتیں اور اپنی قبر اپنے ہاتھوں سے نہ کھودتیں.پس بے شک قیامت کے دن بھی خدا تعالیٰ اپنی نعمتوں کے متعلق لوگوں سے سوال کرے گا
886
Page 895
اور ان سے دریافت کرے گا کہ میری نعمتوں سے تم نے کیا فائدہ اٹھایا.مگر اس دنیا میں بھی جب
قوموں پر تباہی وارد ہوتی ہے تو وہ ایک دوسرے سے کہا کرتی ہیں کہ ہمیں ترقی کا فلاں موقع ملا
مگر ہم نے اس سے فائدہ نہ اٹھایا یا فلاں موقع ملامگر ہم نے اسے ضائع کر دیا.غرض قرآن کریم نے اس سورۃ میں نہایت مختصر الفاظ میں وہ گر بتایا ہے جس سے قومیں تباہ
ہوتی ہیں.اگر اس گر کو ہمیشہ یادر کھا جائے تو کبھی قومی تباہی نہ آئے.محمد رسول اللہ علیم نے
لوگوں کو ہوشیار کر دیا تھا کہ قومی تباہی کی سب سے بڑی وجہ تکاثر ہوتی ہے.مگر افسوس کہ
باوجود اس کے کہ قرآن کریم نے اس حقیقت کو کھول کر بیان کر دیا تھا پھر بھی قومیں اسی طرح
کرتی چلی جاتی ہیں.خدا تعالیٰ کی نعمتیں ان کی نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہیں اور وہ تکاثر کو زیادہ
اہمیت دے کر اپنے آپ کو تباہی کے گڑھے میں گرا لیتی ہیں.( ماخوذ از تفسیر کبیرزیر سورة التكاثر )
887
Page 897
XXXXXXX
بسمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ
بِأَصْحُبِ الْفِيلِ
الَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ
وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيْلَ
تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِيْلٍ
فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُوْلٍ
سورة الفيل
1 - (میں) اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا
( اور ) بار بار رحم کرنے والا ہے ( پڑھتا ہوں )
2.(اے محمد) ! کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے
رب نے ہاتھی ( استعمال کرنے ) والوں کے ساتھ
کیسا سلوک کیا.3.کیا ( ان کو حملہ سے قبل بلاک کر کے ) ان کے
منصو بہ کو باطل نہیں کر دیا.4.اور (اس کے بعد ) ان ( کی لاشوں ) پر مجھنڈ
کے جھنڈ پرندے بھیجے
5.(جو) ان (کے گوشت) کو سخت قسم کے
پتھروں پر مارتے ( اور نوچتے ) تھے.6.سو اس کے نتیجہ میں اس نے انہیں ایسا بھوسا کی
طرح کر دیا جسے جانوروں نے کھا لیا ہو.889
Page 898
حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں:
اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک سورت بھیج کر رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قدر اور
مرتبہ ظاہر کیا ہے اور وہ سورت ہے اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَب الْفِيلِ.یہ سورت اس
حالت کی ہے کہ جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مصائب اور دکھ اٹھا رہے تھے.اللہ تعالیٰ
اس حالت میں آپ کو تسلی دیتا ہے کہ میں تیرا موئید و ناصر ہوں.اس میں ایک عظیم الشان
پیشگوئی ہے کہ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے اصحاب الفیل کے ساتھ کیا کیا.یعنی ان
کا مکر الٹا کر اُن پر ہی مارا اور چھوٹے چھوٹے جانور ان کے مارنے کے لئے بھیج دیے.ان
جانوروں کے ہاتھوں میں کوئی بندوقیں نہ تھیں بلکہ مٹی تھی.سیچیل بھیگی ہوئی مٹی کو کہتے ہیں.اس سورہ شریف میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ قرار دیا ہے اور اصحاب
الفیل کے واقعہ کو پیش کر کے آپ کی کامیابی اور تائید و نصرت کی پیشگوئی کی ہے.یعنی آپ کی ساری کارروائی کو برباد کرنے کے لئے جو سامان کرتے ہیں اور جو تدابیر عمل
میں لاتے ہیں ان کے تباہ کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ ان کی ہی تدبیروں کو اور کوششوں کو الٹا
کر دیتا ہے.کسی بڑے سامان کی ضرورت نہیں ہوتی.جیسے ہاتھی والوں کو چڑیوں نے تباہ
کرد یا ایسا ہی یہ پیشگوئی قیامت تک جائے گی.جب کبھی اصحاب الفیل پیدا ہوگا تب ہی اللہ تعالیٰ
ان کے تباہ کرنے کے لئے ان کی کوششوں کو خاک میں ملا دینے کے سامان کر دیتا ہے.پادریوں...کی چھاتی پر اسلام ہی پتھر ہے ورنہ باقی تمام مذاہب ان کے نزدیک نامرد
ہیں.ہندو بھی عیسائی ہو کر اسلام کے ہی رڈ میں کتابیں لکھتے ہیں.رام چندر اور ٹھا کر داس نے
اسلام
کی تردید میں اپنا سارا زور لگا کر کتابیں لکھی ہیں.بات یہ ہے کہ ان کا کانشنس کہتا ہے کہ
ان کی ہلاکت اسلام ہی سے ہے.طبعی طور پر خوف ان کا ہی پڑتا ہے جن کے ذریعہ ہلاکت
890
Page 899
ہوتی ہے.ایک مرغی کا بچہ بلی کو دیکھتے ہی چلانے لگتا ہے.اسی طرح پر مختلف مذاہب کے
پیروعموماً اور پادری خصوصاً جو اسلام کی تردید میں زور لگا رہے ہیں یہ اسی لئے ہے کہ ان کو یقین
ہے، اندر ہی اندران کا دل ان کو بتاتا ہے کہ اسلام ہی ایک مذہب ہے جو ملل باطلہ کو پیس
ڈالے گا.اس وقت اصحاب الفیل کی شکل میں اسلام پر حملہ کیا گیا ہے.مسلمانوں کی حالت میں
بہت کمزوریاں ہیں.اسلام غریب ہے.اور اصحاب الفیل زور میں ہیں.مگر اللہ تعالیٰ وہی نمونہ
پھر دکھانا چاہتا ہے.چڑیوں سے وہی کام لے گا.ہماری جماعت ان کے مقابلہ میں کیا ہے.ان کے مقابلہ میں بیچ ہے.ان کے اتفاق اور طاقت اور دولت کے سامنے نام بھی نہیں رکھتے.لیکن ہم اصحاب الفیل کا سا واقعہ سامنے دیکھتے ہیں کہ کیسی تسلی کی آیات نازل فرمائی ہیں.مجھے بھی یہی الہام ہوا ہے جس سے صاف صاف پایا جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی نصرت اور تائید
اپنا کام کر کے رہے گی ہاں اس پر وہی یقین رکھتے ہیں جن کو قرآن سے محبت ہے.اگر قرآن
سے محبت نہیں ، اسلام سے اُلفت نہیں وہ ان باتوں کی کب پرواہ کرسکتا ہے.تُو نے دیکھ لیا یعنی تو ضرور دیکھے گا کہ اصحاب الفیل یعنی وہ جو بڑے حملے والے
ہیں اور جو آئے دن تیرے پر حملہ کرتے ہیں اور جیسا کہ اصحاب الفیل نے خانہ کعبہ کو نابود کرنا
چاہا تھاوہ تجھے نابود کرنا چاہتے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا ؟ یعنی ان کا وہی انجام ہوگا جو اصحاب الفیل
کا ہوا.ما خواز تفسیر حضرت مسیح موعود علیہ السلام زیر سورۃ الفیل )
حضرت خلیفہ المسیح الاول رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں :
الخ تر کے معنی آلم تعلم کے ہیں.کیونکہ اصحاب فیل کا واقعہ متواتر بیان سے ایسا
معتبر ومشہور تھا کہ رؤیت اور علم کا حکم رکھتا تھا.جس سال اصحاب فیل تباہ ہوئے ، اسی سال
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے.آپ کی ولادت 5 اپریل 571ء کو ہوئی.891
Page 900
آپ کی ولادت با سعادت کے لئے اصحاب الفیل کا واقعہ بطور توطیہ و تمہید کے تھا.كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ فرما کر ربوبیت کے لفظ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی فرمائی کہ آپ
کی پیدائش سے پہلے ہی جبکہ آپ کے رب نے آپ کی خاطر اس قسم کی صیانت کی ہے کہ
ایک بادشاہ کے زبر دست لشکر کو بلاک کر دیا.تو کیا وہ ربوبیت جبکہ آپ پیدا ہو چکے ہیں تو آپ
سے الگ ہوسکتی ہے.أَلَمْ يَجْعَلُ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ
تضليل کے معنے تدبیر کے اکارت ہونے کے ہیں.گما قَالَ اللهُ تعالی اضل
آغمَالَهُمْ (محمد2) سورۃ محمد کی اس آیت اور آیت بالا دونوں کا ایک ہی مطلب ہے.وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ
ابابیل کے معنے مجھنڈ کے جھنڈ.یہ لفظ جمع ہے.واحد اس کا نہیں ہوتا.ابابیل کے معنے پرے باندھ کر قطار در قطار آنے والے جانوروں کے ہیں.عرب کہا
کرتے ہیں جَاءَتِ الْخَيْلُ آبَابِيْلَ مِنْ هُهُنا وَ مِنْ ھھنا یعنی گھوڑوں کا لشکر قطار باندھ کر اس
طرف سے اور اُس طرف سے آ پہنچا.تَرْمِهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِيلٍ
سیٹیل کے معنے سخت کنکری کے ہیں.جس مقام پر یہ لشکر ہلاک ہوا.وہ مزدلفہ اور مٹی کے درمیان کی جگہ ہے.اب بھی حاجی
لوگ رمی جمار کے لئے اسی میدان سے کنکریاں چن کر ساتھ لے آتے ہیں اور ان سے
رمی جمار کرتے ہیں.ترمِهِمْ بِحِجَارَة : شکاری جانوروں کی عادت ہے کہ وہ گوشت کو پتھر پر مار کر
کھاتے ہیں.892
Page 901
فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ
عضفٍ مأْكُولٍ کے معنے خوید پس خوردہ کے ہیں.چڑیاں ان کی لاشوں کو نوچ کر لے
جاتیں اور پہاڑوں میں کھاتیں.عربی میں ایسے محاورات بکثرت ہیں اور انہی معنوں اور استعاروں میں پرندوں کے الفاظ
وہاں مستعمل ہوتے ہیں چنانچہ النابغة الذبیانی کا شعر ہے ع
إِذَا مَا غَرَا بِجَيْشِ حَلْقَ فَوْقَهُمْ عَصَائِبُ طَيْرٍ تَهْتَدِى بِعَصَائِبِ
جب وہ لشکر لے کر دشمنوں پر چڑھتا تو پرندوں کے غولوں کے غول دشمنوں کی لاشوں کے
کھانے کو جمع ہو جاتے ہیں.اسی قسم کے انداز بیان میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اشارہ کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ
علیہ وسلم کے دشمن بلاک کئے جاویں گے.جیسے فرماتا ہے : أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَتٍ فِي
جو السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (النحل 80)
کیا وہ ان پرندوں کے حالات پر غور نہیں کرتے.جنہیں ہم نے آسمان کی جو میں قابو کر رکھا
ہے.ہم ہی نے تو انہیں تھام رکھا ہے ( اور ایک وقت آنے والا ہے کہ انہیں نبی کریم کے
دشمنوں کی لاشوں پر چھوڑ دیں گے ) مومنوں کے لئے ان باتوں میں نشان ہیں.یہاں بھی پہلے ایک شریر قوم کا بیان کیا ہے.جو بڑی نکتہ چینی کی عادی اور موذی تھی اور
اسلام کو عیب لگاتی تھی.اور بہت سے اموال جمع کر کے فتح کے گھمنڈ میں مکہ پر انہوں نے
چڑھائی کی.یہ ایک حبشیوں کا بادشاہ تھا.جس نے اسی سال مکہ معظمہ پر چڑھائی کی جبکہ
حضرت رحمتہ للعالمین نبی کریم پیدا ہوئے.جب یہ شخص وادی محضر میں پہنچا.اس نے عمائد مکہ
کو کہلا بھیجا کہ کسی معرب ز آدمی کو بھیجو.تب اہل مکہ نے عبدالمطلب نامی ایک شخص کو بھیجا جو
ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے.جب عبدالمطلب اس ابرهه نام بادشاہ کے
پاس پہنچے.وہ مدارات سے پیش آیا.جب عبد المطلب چلنے لگے اس نے کہا کہ آپ کچھ
893
Page 902
مانگ لیں.انہوں نے کہا کہ میری سو اونٹنیاں تمہارے آدمیوں نے پکڑی ہیں وہ واپس بھیج
دو.تب اس بادشاہ نے حقارت کی نظر سے عبد المطلب کو کہا کہ تمہیں اپنی اونٹنیوں کی فکر لگ
رہی ہے اور ہم تمہارے اس معہد کو تباہ کرنے کے لئے آئے ہیں.عبدالمطلب نے کہا کیا
ہمارا مولی جو ذرہ ذرہ کا مالک ہے جب یہ معبد اُسی کے نام کا ہے اور اسی کی طرف منسوب
ہے، وہ اس کی حفاظت نہیں کرے گا؟ اگر وہ اپنے معبد کی خود حفاظت نہیں کرنا چاہتا تو ہم کیا
کر سکتے ہیں.آخر اس بادشاہ کے لشکر میں خطرناک و با پڑی اور چیچک کا مرض جو حبشیوں میں
عام طور پر پھیل جاتا ہے ان پر حملہ آور ہوا اور اوپر سے بارش ہوئی.اور اس وادی میں سیلاب
آیا.بہت سارے لشکری بلاک ہو گئے اور جیسے عام قاعدہ ہے کہ جب کثرت سے مردے ہو
جاتے ہیں.اور ان کو کوئی جلانے والا اور گاڑنے والا نہیں رہتا تو ان کو پرندے کھاتے ہیں.اُن موذیوں کو بھی اسی طرح جانوروں نے کھایا.یہ کوئی پہیلی اور معمنا نہیں.تاریخی واقعہ ہے.ماخوذ از حقائق الفرقان.زیر تفسیر سورۃ الفیل )
حضرت خلیفۃالمسیح الثانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں :
للا سورۃ الفیل مکہ میں نازل ہوئی.اس سورۃ کا تعلق پہلی سورۃ سے ایک تو اس لمبے تعلق کو مدنظر رکھتے ہوئے ہے.یعنی
قرآن کریم کی یہ آخری سورتیں سوائے چند آخری سورتوں کے باری باری اسلام کے ابتدائی
زمانہ کے متعلق اور اسلام کے آخری زمانہ کے متعلق آتی ہیں.ایک سورۃ میں اسلام کے
ابتدائی زمانہ کا خصوصیت سے ذکر ہوتا ہے اور دوسری سورۃ میں اسلام کے آخری زمانہ کا
خصوصیت سے ذکر ہوتا ہے.میری یہ مراد نہیں کہ جس سورۃ میں اسلام کے ابتدائی زمانہ کا ذکر
آتا ہے اس میں آخری زمانہ کا ذکر نہیں ہوتا اور نہ یہ کہ جس سورۃ میں اسلام کے آخری زمانہ کا
ذکر آتا ہے اس میں ابتدائی زمانہ کا ذکر نہیں ہوتا.بالعموم دونوں ہی ذکر ہوتے ہیں.لیکن
خصوصیت کے ساتھ ایک سورۃ میں مد نظر اسلام کا ابتدائی زمانہ ہوتا ہے اور دوسری سورۃ میں
894
Page 903
خصوصیت کے ساتھ مڈ نظر اسلام کا آخری زمانہ ہوتا ہے.پس یہ سورتیں خصوصیت کے لحاظ
سے ابتدائی یا آخری زمانہ سے تعلق رکھتی ہیں.یہ نہیں کہ پہلے اور دوسرے زمانہ کا اکٹھا ذ کر نہیں
ہوتا.بسا اوقات بڑے زور سے ہوتا ہے.مگر وہ مقصود اول نہیں ہوتا.مقصود اول صرف ایک
ذکر ہوتا ہے اور یہ دور باری باری چلتا ہے.اس لحاظ سے سورۃ الفیل آخری زمانہ کے متعلق
معلوم ہوتی ہے یعنی اس میں خصوصیت کے ساتھ آخری زمانہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے.گو
ذکر اس میں پہلے زمانہ کا ہے مگر مقصودآخری زمانہ کی طرف اشارہ کرتا ہے.قریبی ترتیب کے لحاظ سے اس سورۃ کا تعلق پہلی سورۃ سے یہ ہے کہ پہلی سورۃ میں یہ
بتایا گیا تھا کہ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ تُمَزَةٍ.عیب چینیاں کرنے والے، دوسروں کو نقصان
پہنچانے والے اور تکلیفیں دینے والے لوگ جو اپنے مال اور دولت پر گھمنڈ کرتے ہیں وہ تباہ
اور برباد کئے جائیں گے.یہ حکم تو عام تھا کیونکہ فرماتا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ أُمَزَةٍ.ہر ایسے شخص
پر عذاب آئے گا جو هُمَزَةٍ اور لُمَزَةٍ ہو گا لیکن مقصود اول اس میں رسول اللہ علی ایم کے مخالف
تھے.رسول کریم عالم کے زمانہ میں آپ کے دشمن مالدار تھے، دولتمند تھے، ان کی بڑی
بڑی تجارتیں تھیں ، بڑی بڑی جائیداد میں تھیں.تمام ملکی اقتدار ان کے قبضہ میں تھا اور وہ اپنے
مال و دولت اور رتبہ کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے اور خیال کرتے تھے کہ ان طاقتوں
اور قوتوں کی وجہ سے محمد رسول اللہ علیم اور ان کے ساتھی کسی صورت میں بھی ان پر غالب نہیں
آ سکتے.اللہ تعالیٰ نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ہے تمہارا یہ خیال کہ محمد رسول اللہ
الایی تم پر غالب نہیں آ سکتے قطعی طور پر غلط اور بے بنیاد ہے.محمد رسول اللہ صلی ضرور
غالب آئیں گے اور تم لوگ جو بڑے کہلاتے ہو اور مال و دولت کے غلط استعمال کی وجہ سے
غریبوں کو ستاتے اور دکھ دیتے ہو نا کام ونامرادر ہو گے.غرض اس سورۃ میں یہ خبر دی گئی تھی کہ
یہ لوگ بڑے دکھ میں بتلا ہوں گے.ان
کی تباہی کامل ہوگی اور ان
کا انجام نہایت دردناک ہو
گا.یہاں قدرتی طور پر سوال پیدا ہوتا تھا کہ ایسا کس طرح ہوگا ؟ عقل میں تو یہ نہیں آسکتا کہ
895
Page 904
بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے عقلمند، بڑے بڑے مدبر اور بڑی بڑی طاقتوں والے ہار
جائیں اور کمز ور جیت جائیں.جن کے پاس حکومت ہو وہ تو شکست کھا جائیں اور جو ہمسایوں
کے مظالم کا شکار ہورہا ہو وہ فتح حاصل کر لے.پس چونکہ یہ اعتراض پیدا ہوتا تھا کہ عقل اس
بات کو نہیں مان سکتی.اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ میں ایک ایسا واقعہ پیش کیا ہے جسے
کوئی عقل نہیں مان سکتی تھی.اس میں جو کچھ ہوا الہی تقدیر کے ماتحت ہوا اور عقل کے بالکل
خلاف نتیجہ پیدا ہوا اور دنیا کو تسلیم کرنا پڑا کہ اس دنیا میں صرف وہی کچھ نہیں ہوتا جو عقل کے
مطابق ہو بلکہ ایسے واقعات بھی رونما ہو جایا کرتے ہیں جو عقل کے خلاف ہوتے ہیں جیسا کہ
اصحاب الفیل کا واقعہ ہے.ایک بادشاہ نے جس کی بہت بڑی اور منظم حکومت تھی مکہ پر حملہ کیا.مگر باوجود ساری
طاقتوں اور قوتوں کے وہ ہار گیا اور مکہ کے لوگ جو بے سر و سامان تھے جیت گئے.یوں تو هُمَزَة
اور لمرة ہر جگہ ہوتے ہیں مگر اس جگہ پہلے مخاطب مگہ کے هُمَزَۃ اور لمزة ہی تھے اور انہیں کے
متعلق یہ کہا گیا تھا کہ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَ عَمَّدَة يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ اخْلَدَہ.وہ لوگ یہ سمجھتے تھے
کہ ہم مال و دولت کے زور سے غالب آجائیں گے اور محمد رسول اللہ عالم ہمارے مقابلہ میں
بار جائیں گے.اللہ تعالیٰ ان مکہ والوں کو فرماتا ہے کہ تمہارے مکہ میں ایک مثال موجود ہے.تم جو محمد رسول اللہ علیم کے مقابلہ میں اپنے آپ کو بڑا کہہ رہے ہو تمہیں یادرکھنا چاہئے کہ تم
سے بھی بڑے بڑے لوگ دنیا میں موجود تھے.تم سے بھی بڑی بڑی حکومتیں دنیا میں موجود
تھیں.چنانچہ انہیں حکومتوں اور طاقتوں میں سے ایک نے مکہ پر حملہ کیا اور تم لوگوں نے بغیر
مقابلہ کئے اس کے سامنے ہتھیار ڈال دیئے.لیکن مکہ چونکہ خدا کے ایک پیارے کا صدر مقام
بننے والا تھا اور چونکہ وہ خدا تعالیٰ کی ایک پیاری جگہ اور اس کا مقدس مقام تھا.اللہ تعالیٰ نے
دشمن کے ارادوں کو باطل کر دیا اور اس کی تدبیروں کو توڑ کر رکھ دیا.چنانچہ آخر مکہ ہی غالب رہا
اور وہ بڑا طاقتور دشمن ناکام و نامرادر ہا.یہ مثال تمہارے سامنے موجود ہے.عقل میں وہ بات
896
Page 905
بھی نہیں آتی تھی.مگر آخر ہوا وہی جو اللہ تعالیٰ کا منشاء تھا.کیا اس مثال کو دیکھتے ہوئے اب بھی
تمہاری سمجھ میں نہیں آتا کہ محمد رسول اللہ صل العالم جن کے پاس کوئی مال نہیں، کوئی دولت نہیں،
کوئی جتھہ نہیں، کوئی طاقت نہیں وہ کس طرح جیت جائیں گے اور مکہ والے جو طاقتور اور جتھہ
والے ہیں ان کے مقابلہ میں کس طرح ہار جائیں گے.تم اصحاب الفیل کے واقعہ کو مدنظر رکھو
اور یہ سمجھ لو کہ جس طرح وہاں ہوا اسی طرح اللہ تعالیٰ اس موقعہ پر بھی اپنی قدرت کا زبردست نشان
دکھائے گا اور تمہیں محمد رسول اللہ صل تعلیم کے مقابلہ میں مغلوب کر دے گا.دوسرا تعلق اس سورۃ کا پہلی سورۃ سے یہ ہے کہ اس میں دلیل بالاولیٰ کے طور پر اس امر
کی طرف اشارہ ہے کہ خانہ کعبہ مقصود بالذات نہیں تھا بلکہ خانہ کعبہ ایک علامت تھی آنے
والے کی.ایک عظیم الشان انسان نے دعائے ابراہیمی کے ماتحت دنیا کی ہدایت کے لئے
آنا تھا اور اس کے لئے ایک مرکز کی ضرورت تھی.اسی کے لئے اللہ تعالیٰ نے اس مقام کو
مقدس قرار دیا اور اسے لوگوں کا مرجع بنا دیا.مگر بہر حال یہ مقصود نہیں تھا.مقصود وہی تھا جس
نے دعائے ابراہیمی کے ماتحت ظاہر ہونا تھا اور جس کا کام یہ بتایا گیا تھا کہ يَتْلُوا عَلَيْهِمُ
آيَاتِهِ وَيُزَليهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَب وَالْحِكْمَةَ.وہ خدا کی آیتیں انہیں پڑھ پڑھ کر سنائے گا.ان کے دلوں کو پاک کرے گا.انہیں احکام الہیہ کی حکمتیں سکھائے گا.انہیں خدا تعالی کی
شریعت کے اسرار سمجھائے گا.اور ان میں پاکیزگی اور طہارت پیدا کرے گا.یہ انسان اصل
مقصود تھا.مکان اصل مقصود نہیں تھا.مکان تو صرف ایک علامت تھی.اصل اہمیت رکھنے
والی وہ چیز تھی جو اس کے پیچھے تھی.ا خانہ کعبہ کو اگر عزت حاصل تھی تو اس لئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی
بنیادیں اٹھائیں تا موعود گل ادیان ظاہر ہو کر اس سے تعلق پیدا کرے اور اللہ تعالیٰ نے اسے
لوگوں کے لئے ایک مقام اتحاد اور اقوام عالم کے لئے مرجع بنا دیا.اسی نقطہ نگاہ کے ماتحت
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم یہ تو دیکھو کہ محمد رسول اللہ علیم کا دعوی کیا ہے.محمد رسول اللہ علیم کا
897
Page 906
دعوی یہ ہے کہ میں وہ شخص ہوں جس کے ظہور کے لئے خانہ کعبہ کی بنیاد رکھتے وقت
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں کی تھیں تم کہتے ہو کہ یہ غریب ہے کمزور ہے، ناطاقت
ہے اور ہم بڑے دولتمند ہیں یہ ہمارے مقابلہ میں نہیں ٹھہر سکتا.تمہیں سمجھنا چاہئے کہ خانہ کعبہ کی
قیمت زیادہ ہے یا محمد رسول اللہ علیم کی قیمت زیادہ ہے.خانہ کعبہ کی تو بنیاد ہی اسی لئے رکھی
گئی تھی کہ محمد رسول اللہ میں ظاہر ہوں.چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت جو دعا
کی اس میں کھلے طور پر یہ الفاظ آتے تھے کہ وَابْعَثُ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ
ايتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الكتب وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمُ (البقرۃ 130) پس خانہ کعبہ قائم ہی اسی لئے
کیا گیا تھا کہ تمام بنی نوع انسان کو مخاطب کرنے والا نبی اس جگہ پیدا ہو.اگر علامت کے
لئے خدا نے یہ نشان دکھایا تھا کہ اس نے ابرہہ اور اس کے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا تو تم سمجھ لو کہ
اس مقصود کے لئے وہ کتنا بڑا نشان ظاہر کرے گا.جب ایک علامت کے لئے اس نے
اصحاب الفیل کو تباہ کر دیا تو وہ چیز جو مقصود بالذات ہے اس کے لئے تو وہ جتنی بھی غیرت
دکھائے کم ہے.حالانکہ اصحاب الفیل کو جو طاقت حاصل تھی وہ مکہ والوں کو نہیں تھی.گویا مگہ
والوں کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہاری تو کوئی حیثیت ہی نہیں.تم تو اصحاب الفیل کے مقابلہ
میں بھی ذلیل تھے.جب تمہارے جیسے ذلیل انسانوں کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے
اصحاب الفیل کے حملہ سے مکہ کو بچایا تو کیا تم یہ خیال کر سکتے ہو کہ تمہارے حملہ سے وہ
محمد رسول اللہ میل تعلیم کو نہیں بچائے گا.تیسرا قریبی تعلق پہلی سورۃ سے یہ ہے کہ اس میں بتایا گیا ہے کہ مکہ کا بچانا بھی گو
اصحاب الفیل کی تباہی کی ایک وجہ تھی.مگر اصل وجہ محمد رسول اللہ علیم کی حفاظت تھی اور یہ
مقصد اور تمام مقاصد سے زیادہ مقدم اور اہم تھا.اس میں کوئی شبہ نہیں کہ خانہ کعبہ کو بچانا خود
بھی ایک مقصود تھا مگر بعض دفعہ ایک سے زیادہ بھی مقصود ہو جاتے ہیں.اللہ تعالیٰ اس جگہ فرماتا ہے کہ تم کہتے ہو محمد رسول اللہ علیم کس طرح جیت جائیں
898
Page 907
گے.محمد رسول اللہ صل العلم تو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی خاطر
اصحاب الفیل کو تباہ کر دیا.اب کیا تم سمجھتے ہو کہ محمد رسول اللہ علی ایم کی پیدائش سے پہلے تو اس
نے آپ کے لئے ایسا عظیم الشان نشان دکھا دیا تھا مگر پیدا ہونے کے بعد وہ آپ کو چھوڑ دے
گا.جس انسان کی حیثیت اتنی عظیم الشان تھی کہ اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے
اس کے لئے اپنے نشانات کو ظاہر کرنا شروع کر دیا تھا تم سمجھ سکتے ہو کہ اس کے پیدا ہونے کے
بعد اللہ تعالیٰ کو اس کا کتنا بڑا احترام ملحوظ ہو گا اور اس کی عظمت کے اظہار کے لئے وہ کیا کچھ نہ کرے
گا.پس تمہیں اپنا فکر کر لینا چاہئے ایسا نہ ہو کہ تم اس کی مخالفت میں اپنی عاقبت تباہ کرلو.چوتھا قریبی تعلق اس سورۃ اور پہلی سورۃ کا یہ ہے کہ پہلی سورۃ میں دشمن کے مال و
دولت کے مالک ہونے کا دعوی بیان کیا گیا تھا.دشمن کا دعویٰ تھا کہ میں بڑا مالدار ہوں اور
اس کی وجہ سے میں ہمیشہ ہمیش قائم رہوں گا.اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب الفیل
کے واقعہ کو پیش کیا ہے اور بتایا ہے کہ اصحاب الفیل بھی بڑے دولتمند تھے اور ان کی دولت
سے تمہاری دولت زیادہ نہیں.مگر باوجود اس کے کہ وہ بڑے دولتمند تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو
تباہ کر دیا.پانچواں قریبی تعلق اس سورۃ کا پہلی سورۃ سے یہ ہے کہ بعض لوگ یہ اعتراض کر دیا
کرتے ہیں کہ اگلے جہان کے عذاب سے لوگوں کو ڈرانے کا فائدہ کیا ہے؟ پہلی سورۃ میں
فرمایا گیا تھا کہ كَلَّا لَيُنَبَذَنَ فِي الْحُطَمَةِ.وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللهِ الْمُوْقَدَةُ الَّتِي
تطلعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ فِي عَمَلٍ مُمدَّدَة (الهمزة 5-10) میں بتا چکا ہوں کہ
ان آیات میں خصوصیت سے اس دنیا کے عذاب کا ذکر کیا گیا ہے.مگر اس کے ظاہری معنے
چونکہ یہی نظر آتے ہیں کہ اگلے جہان میں کفار پر اس رنگ میں عذاب نازل ہوگا.اس قسم کی
آیات پر کفار شور مچا دیا کرتے ہیں کہ اگلا جہان تو کسی نے دیکھا نہیں.پس تم اگلے جہان کے
عذابوں کا ذکر کر کے در حقیقت لوگوں کو دھوکا دیتے ہو.اور ایک ایسی بات پیش کرتے ہو جس
899
Page 908
کی تصدیق اس دنیا میں نہیں ہو سکتی.جیسے اب تک بھی یورپین مصنف یہی اعتراض کرتے ہیں
کہ قرآن کریم نے اگلے جہان کے عذابوں سے ڈرا ڈرا کرلوگوں کو مسلمان کر لیا.یہی عرب
لوگ کہتے تھے کہ قرآن کریم ایسے عذابوں کی خبر دیتا ہے جو اس جہان سے تعلق نہیں رکھتے وہ
صرف ایسے عذابوں کا ذکر کرتا ہے جو اگلے جہان سے تعلق رکھتے ہیں اور اگلا جہان ہم
نہیں مانتے.پھر ہم ان باتوں کو کس طرح درست تسلیم کرلیں.اس کے جواب کے لئے
قرآن کریم کا یہ طریق ہے کہ جہاں وہ کسی اخروی عذاب یا انعام کا ذکر کرتا ہے وہاں کسی نہ کسی
دنیوی عذاب یا انعام کا ضرور ذ کر کرتا ہے، یہ بتانے کے لئے کہ تم اُخروی عذاب یا انعام یا نتیجہ
کے متعلق تو کہہ سکتے ہو کہ ہم ان باتوں کو کس طرح مان لیں یہ تو اگلے جہان سے تعلق رکھتی
ہیں.مگر تم دنیوی امور کے متعلق یہ بات نہیں کہہ سکتے اس لئے ہم اُخروی عذابوں یا
انعاموں کے ذکر کے ساتھ ہی بعض دنیوی امور سے تعلق رکھنے والی پیشگوئیوں کا بھی ذکر کرتے
ہیں جو موجودہ حالات میں بالکل ناممکن نظر آتی ہیں.اگر یہ ناممکن نظر آنے والی باتیں ممکن ہو
جائیں اور تمہاری آنکھوں کے سامنے یہ باتیں پوری ہو جائیں تو تمہیں سمجھ لینا چاہئے کہ جس
خدا نے ان غیر ممکنات کو ممکنات کی صورت دے دی ہے وہ اُخروی عذابوں کو بھی اسی رنگ
میں پورا کرنے کی طاقت رکھتا ہے.اسی وجہ سے قرآن کریم کا یہ ایک عام قانون ہے کہ وہ
اُخروی اور دنیوی عذابوں اور انعاموں کو آپس میں ملا کر بیان کرتا ہے تا کہ وہ دنیوی عذاب اور
انعام اُخروی عذابوں اور انعاموں کی صداقت پر گواہ ہوں اور کفار ان کے انکار کی جرات نہ کر
سکیں.غرض اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفیل کو کفار کے اس اعتراض کے جواب میں بیان کیا ہے کہ
اگلے جہان کے عذابوں کا کیا اعتبار ہوسکتا ہے.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہیں یہ بات عقل کے
خلاف اور ناممکن نظر آتی ہے مگر ایسی ہی ناممکن بات اصحاب الفیل کی بربادی کی بھی تھی.ان کا
حملہ ایسے رنگ میں ہوا اور ایسے حالات میں ہوا اور عربوں کا دفاع اتنا کمزور پڑ گیا اور انہوں
900
Page 909
نے اپنے آپ کو ابرہہ اور اس کے لشکر کے مقابلہ میں اتنا بیکس اور بے بس پایا کہ ہتھیار ڈال
دیئے اور سمجھ لیا کہ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے مگر باوجود اس کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے
سامانوں اور ذرائع سے دشمن کو تباہ کیا گیا کہ جس کی مثال دنیا میں ڈھونڈے سے بھی نہیں مل
سکتی.فرماتا ہے تم غور کرو اور سوچو کہ وہاں کیا بات تھی اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کے لشکر
کو تباہ کیا.اس کا لشکر اس لئے تباہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا
کی تھی جس کے نتیجہ میں خدا تعالیٰ نے ان سے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ اس شہر کو امن والا بنائے گا
اور اسے دشمنوں کے حملہ سے محفوظ رکھے گا.ابراہیم کے وقت لوگ کہتے ہوں گے کہ جناب آپ
نے یہ دعویٰ تو کر دیا ہے مگر اس کا ثبوت کیا ہے.یہ تو آئندہ زمانہ کے متعلق آپ ایک بات کہہ
رہے ہیں اور اُس زمانہ میں نہ ہم زندہ ہوں گے ، نہ آپ نے زندہ رہنا ہے.پھر ایسی بات کا
فائدہ کیا ہے.مگر جب وہ وقت آیا دیکھنے والوں نے دیکھ لیا کہ ابراہیم کی پیشگوئی پوری ہوئی اور
ایک زبر دست دشمن جولشکر جرار کے ساتھ خانہ کعبہ پر حملہ آور ہوا تھا اس سے اللہ تعالیٰ نے
اپنے گھر کو بچالیا اور اس طرح ایک ناممکن بات ممکن ہوگئی.جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
یہ پیشگوئی کی تھی اُس وقت مکہ دنیا میں کوئی شہر نہیں تھا.محض اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی رضا
کے لئے انہوں نے اپنی بیوی اور ایک چھوٹے بچے کو جو ابھی بالغ بھی نہیں ہوا تھا اس مقام پر
آکر چھوڑ دیا.اس وقت تک ابھی زمزم کا چشمہ بھی نہیں پھوٹا تھا.بالکل وادی غیر ذی زرع کی
سی حالت تھی.نہ اس میں پانی کا کوئی سامان تھا.صرف ایک مشکیزہ پانی اور ایک تھیلی خشک
کھجوروں کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے پاس رکھ دی اور اللہ تعالی کے حکم کے
ماتحت وہ اپنی بیوی اور بچے کو وہاں چھوڑ کر واپس چل پڑے.انہوں نے اپنی بیوی کو بتایا
نہیں کہ میں تمہیں یہاں اکیلے چھوڑ کر جارہا ہوں کیونکہ انہیں خیال گزرا کہ ماں کی مامتا اپنے بچہ
کی تکلیف کی وجہ سے شاید اس کی برداشت نہ کر سکے.جب حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے تو
آپ نے اس محبت کی وجہ سے جو طبعاً انسان کو اپنی بیوی اور بچے سے ہوتی ہے تھوڑی تھوڑی
901
Page 910
دیر کے بعد انہیں مُڑ کر دیکھنا شروع کر دیا.پہلے تو وہ اس رنگ میں باتیں کرتے رہے کہ بیوی
کو یہ شبہ پیدا نہ ہوا کہ میں انہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اور جب وہاں سے واپس چلے تو واپس کو ٹتے
وقت بھی اس انداز میں واپس گئے جیسے کوئی ایندھن اکٹھا کرنے جاتا ہے یا پانی کا انتظام
کرنے کے لئے جاتا ہے.مگر جب چل پڑے تو ان سے برداشت نہ ہوسکا اور تھوڑے فاصلہ
پر جا کر انہوں نے اپنی بیوی اور بچے کی طرف دیکھا اور پھر چلے اور چند قدم اٹھائے تو محبت نے
غلبہ پایا اور انہوں نے اپنی بیوی اور بچے پر نظر ڈالی.حضرت ہاجرہ اپنے خاوند کی ان حرکات
سے سمجھ گئیں کہ یہ جدائی عارضی نہیں بلکہ معلوم ہوتا ہے یہ مستقل طور پر جا رہے ہیں.کیونکہ ان
رض
کے چہرے پر رقت کے آثار تھے اور ان کی آنکھوں میں آنسو آئے ہوئے تھے.حضرت ہاجرہ
نے سمجھ لیا کہ بات کچھ اور ہے.وہ گھبرا کر اٹھیں اور حضرت
ابراہیم کے پاس گئیں اور کہا کہ کیا
آپ ہم کو چھوڑے چلے جار ہے ہیں.حضرت ابراہیم رقت کی وجہ سے کوئی جواب نہ دے
سکے.ان کا گلا پکڑا گیا.ان کی آنکھوں میں آنسو آگئے اور انہوں نے اپنا منہ پھیر لیا.حضرت
رض
رض
باجرہ کو یقین آ گیا کہ اب یہ ہم کو مستقل طور پر چھوڑے چلے جارہے ہیں.چونکہ حضرت ہاجرہ
کا پہلے بھی اپنی سوت کے ساتھ جھگڑا ہو چکا تھا اس لئے انہیں خیال آیا کہ شاید یہ اس کی وجہ سے
نہ ہو.پھر خیال آیا کہ چونکہ حضرت ابراہیم اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اس لئے شاید اللہ تعالیٰ نے ہی
ان کو اس بات کا حکم نہ دیا ہو.چنانچہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اللہ
امرك.کیا خدا نے آپ کو حکم دیا ہے کہ ایسا کرو.حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اثبات میں
سر بلاد یا.مگر غم کی وجہ سے ان سے بات نہیں کی گئی.حضرت ہاجرہ نے یہ سن کر کہا اگر خدا نے
آپ کو یہ حکم دیا ہے تو خدا ہم کو چھوڑے گا نہیں.آپ بیشک چلے جائیں.جس وقت حضرت
ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور بیٹے کو وہاں چھوڑا ہے اُس وقت مکہ کوئی شہر نہیں تھا.وہاں کھانے کی کوئی چیز نہیں تھی.صرف ایک مشکیزہ پانی کا اور ایک تھیلی کھجوروں کی وہ انہیں
دے کر واپس چلے گئے اور اس لئے گئے کہ خدا نے ان سے کہا تھا کہ تو اپنے بیٹے کو ہماری راہ
رض
902
Page 911
میں ذبح کر.میرا کامل یقین ہے اور میں نے متواتر یہ بات بیان کی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ میں
اسے قرآن کریم سے ثابت کر سکتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رویا میں جو یہ دیکھا تھا
کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں اس سے مراد ظاہری ذبح کرنا نہیں تھا بلکہ اس سے مراد یہ
تھی کہ ایک وقت آپ کو حکم دیا جائے گا کہ آپ اپنے بیٹے اسماعیل کو ایک ایسی وادی
غیر ذی زرع میں جا کر چھوڑ آئیں جہاں نہ پینے کے لئے پانی ہو اور نہ کھانے کے لئے غلہ.ایک جنگل اور دہشتناک بیابان میں جہاں ہر وقت اس بات کا امکان تھا کہ بھیڑیا آئے اور
انہیں کھا جائے.جہاں کھانے اور پینے کی کوئی چیز نہ تھی.جہاں رہائش کے لئے کوئی مکان
نہیں تھا.جہاں سینکڑوں میل تک آبادی کا کوئی نشان تک نہ تھا.حضرت ابراہیم علیہ السلام کا
اپنے بیٹے اسماعیل کو چھوڑ نا قتل سے کسی طرح کم نہیں تھا بلکہ زیادہ ہی تھا.قتل کرتے وقت تو
مقتول کی ایک منٹ میں جان نکل جاتی ہے مگر یہاں اس بات کا امکان تھا کہ وہ بھو کے اور
پیاسے کئی کئی دن تک تڑپ تڑپ اور سسک سسک کر جان دیں.پس میرے نزدیک
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو خواب دیکھی تھی اس میں اسی طرف اشارہ تھا کہ ایک دن
تمہیں حکم دیا جائے گا کہ جاؤ اور اسماعیل کو جنگل میں چھوڑ آؤ.کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ ایک
ایسی جگہ پر جس میں کشش کے کوئی سامان نہیں ، جس میں کھانے پینے کے کوئی سامان نہیں،
جس میں رہائش کا کوئی سامان نہیں اپنا گھر بنائے.اور پھر اس گھر کو ترقی دے کر ایک بستی کی
شکل دے اور اس بستی میں ایک ایسی قوم پلتی چلی جائے جس میں اس کا آخری نبی دنیا کی
ہدایت کے لئے مبعوث ہو.اس غرض کے لئے خدا تعالیٰ نے ایک جنگل کو چنا اور اس لئے چنا
تا وہ خطہ بیرونی دنیا کے تعیش سے محفوظ رہے.اس میں کوئی شبہ نہیں کہ عرب میں بت پرستی
بھی تھی.بے دینی بھی تھی.بے حیائی بھی تھی.اور وہ قوم شرک کے انتہا کو پہنچ چکی تھی.مگر اس
میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ انسانیت کا جوہر جیسے عرب میں قائم تھا ویسا دنیا میں اور کہیں قائم نہیں تھا
اور اس کی وجہ یہی ہے کہ مکہ کے لوگ ایک جنگل میں پڑے ہوئے تھے اور دنیوی تعیش کے
903
Page 912
سامانوں سے بہت دُور تھے.بیشک ان میں بعض دولتمند بھی تھے مگر دنیا کی دولت کے مقابلہ
میں ان کی دولت ایسی ہی تھی جیسے کسی احمدی کے پاس اگر لا کھ دولاکھ روپے ہوں تو وہ اپنے آپ
کو بہت بڑا امیر سمجھ لیتا ہے.حالانکہ یورپ کے کئی کارخانہ دار ایسے ہیں جن کے ملازموں کے
ملازموں کے پاس اس سے زیادہ دولت ہوتی ہے.مکہ کی دولت بھی اس وقت کی معلومہ دنیا کی
دولت کے مقابلہ میں بالکل حقیر تھی اور یہ جو کچھ ہوا اللہ تعالی کی حکمت کے ماتحت ہوا.اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ مکہ میں ایک ایسی قوم بسادے جو دولتمند دنیا اور عیش والی دنیا سے الگ
رہتے ہوئے انسانی جوہروں کو قائم رکھ سکے.چنانچہ محمد رسول اللہ ایم کی کامیابی کا ایک بڑا
ذریعہ یہی تھا کہ آپ کو عرب قوم مل گئی جس نے قربانی اور ایثار کا وہ نمونہ دکھایا جس کی مثال
دنیا کے پردہ پر نہیں مل سکتی.انہوں نے جس رنگ میں اپنی جانوں کی قربانی پیش کی ہے اس کی
مثال دنیا میں اور کہیں نہیں ملتی.اس طرح وہ قوم اسلام کے پھیلنے اور اس کی اشاعت کا ایک
ذریعہ بن گئی.بہر حال خانہ کعبہ کی بنیاد رکھتے وقت اور اپنی اولاد کو وہاں بساتے وقت حضرت ابراہیم
علیہ السلام کو کوئی طاقت اور قوت حاصل نہیں تھی.اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
جب یہ خبر دی کہ خدا ایک نبی کو میری اولاد میں مبعوث کرے گا جو دنیا کے لئے مرجع ہو جائے گا
اور جب انہوں نے دعا کی کہ الہی دنیا کے چاروں طرف سے لوگ یہاں آئیں اور حج کریں اور
عبادت اور ذکر الہی میں اپنا وقت گزاریں اور تیرا نام بلند کریں اور تسبیح و تحمید کریں تو کیا
انہیں طاقت حاصل تھی کہ وہ لوگوں کو کھینچ لاتے؟ وہ تو خود اپنی بیوی اور بچے کو وہاں مرنے کے
لئے چھوڑ گئے تھے انہوں نے کسی اور کو کیا لا نا تھا؟ مگر پھر خدا نے مکہ کی آبادی کے کیسے سامان
کئے اور ان کی دعا کو کس حیرت انگیز رنگ میں پورا فرمایا.حضرت ابراہیم علیہ السلام جب
واپس چلے گئے تو چند دنوں کے بعد پانی ختم ہو گیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس کی شدت
سے تڑپنے لگے.ماں سے اپنے بچہ کی حالت دیکھی نہ گئی تو انہوں نے صفا ومروہ پر چڑھ کر دیکھنا
904
Page 913
چاہا کہ شاید ادھر اُدھر کوئی آدمی نظر پڑ جائے اور وہ ان کے لئے پانی کا انتظام کر دے یا پانی کا
کچھ پتہ دے.مگر وہاں آدمی کہاں؟ آخر جب بہت بیتاب ہو گئیں تو انہیں کسی کی آواز سنائی
دی.اس پر انہوں نے بلند آواز سے کہا اے خدا کے بندے تو جو کوئی بھی ہے میں تجھے قسم دیتی
ہوں کہ اگر تجھے پانی کا پتہ ہے تو مجھے بتا کیونکہ میرا بچہ پیاسا مر رہا ہے.اس کے جواب میں اس
آواز دینے والے نے کہا.ہاجرہ ! میں خدا کا فرشتہ ہوں.جا اور دیکھ کہ خدا نے اسماعیل کے
قدموں کے نیچے پانی کا ایک چشمہ پھوڑ دیا ہے.چنانچہ وہ آئیں اور انہوں نے دیکھا کہ واقعہ
میں زمین میں سے ایک چشمہ پھوٹ رہا ہے.یہی چشمہ زمزم کہلاتا ہے.اور اسی تبرک کی
وجہ سے لوگ اس کا پانی ڈور ڈور لے جاتے ہیں بلکہ بعض لوگ وہاں اپنا کفن لے جاتے اور
زمزم کے پانی سے گیلا کر کے لے آتے ہیں.پھر حجر ہم قبیلہ وہاں سے گزرا.اس قبیلہ کے آدمی
چونکہ اسی راستہ سے یمن میں تجارت کے لئے جاتے تھے اور پانی نہ ملنے کی وجہ سے ان میں سے
بعض مرجاتے تھے.جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں پانی موجود ہے تو انہوں نے خواہش کی کہ
یہاں ایک درمیانی پڑاؤ بنا لیا جائے.چنانچہ جب ہم قبیلہ کا رئیس حضرت ہاجرہ کے پاس آیا اور
اس نے درخواست کی کہ ہمیں یہاں بسنے کی اجازت دی جائے ہم آپ کی رعایا بن کر رہیں
رض
رض
گے.حضرت ہاجرہ نے اس کی اس درخواست کو منظور فرما لیا اور اس طرح وہ ایک درمیانی
پڑاؤ بن گیا جہاں حجر ہم قبیلہ کے اور بھی کئی لوگ رہنے لگ گئے.رفتہ رفتہ اس پڑاؤ نے ایک
گاؤں کی شکل اختیار کر لی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اسی قبیلہ کی ایک لڑکی سے شادی
کرلی.بھلا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس جنگل میں جہاں سینکڑوں میل تک آبادی نہ تھی
کہاں سے بیوی لانی تھی.خدا نے ہی یہ سامان کیا کہ وہاں مجر ہم قبیلہ کا ایک گاؤں بسا دیا.اس
طرح ان کو بیوی بھی مل گئی اور ان کی اولاد کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا.مگر جب حضرت ابراہیم
علیہ السلام نے مگہ آباد کیا تھا اس وقت کون کہہ سکتا تھا کہ یہ ملہ کسی دن شہر بن جائے گا.کون
کہہ سکتا تھا کہ لوگ یہاں آئیں گے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنا وقت گزاریں گے.کون
905
Page 914
کہہ سکتا تھا کہ یہ شہر ہمیشہ محفوظ رہے گا اور اللہ اسے امن والا بنائے گا.اس زمانہ کے حالات
کے لحاظ سے یہ تمام باتیں ناممکن تھیں.کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ مکہ شہر بنے گا.کوئی
شخص یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ مکہ محفوظ رہے گا.مگر اصحاب الفیل کے حملہ کے وقت وہ جو حضرت
ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ مکہ ایک شہر بنے گا اور شہر بھی ایسا جو دشمن کے حملہ سے محفوظ
رہے گا.اللہ تعالیٰ نے اس کو پورا کر کے دکھا دیا.ا مگر سوال یہ ہے کہ اصحاب الفیل کو اس وقت تک کس نے حملہ کرنے سے روکے رکھا
تھا؟ آخر کونسی طاقت تھی جو اس عرصہ دراز میں مکہ کی محافظ رہی.حضرت ابراہیم اور
اصحاب الفیل کے واقعہ کے درمیان کوئی 28 سو سال کا فرق تھا.یا بعض روایتوں کے لحاظ
سے 22 سو سال کا فرق تھا.دو ہزار دوسو یا دو ہزار آٹھ سو سال تک مکہ پر کوئی حملہ نہیں کرتا.دو
ہزار دو سو سال تک مکہ کے گرانے کی خواہش کسی کے دل میں پیدا نہیں ہوتی.دو ہزار دوسوسال
تک خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کا جوش کسی کے دل میں پیدا نہیں ہوتا.نہ کسی یہودی کے دل
میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے.نہ کسی عیسائی کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے.نہ کسی اور حکومت
کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے.اس عرصہ میں شمور کی حکومت آئی ، عاد کی حکومت آئی.یہ
بڑی بڑی حکومتیں تھیں اور ان کی طاقت بہت زیادہ تھی مگر کسی کو یہ خیال پیدا نہ ہوا کہ وہ خانہ
کعبہ پر حملہ کرے.لیکن ادھر ربیع الاول میں محمد رسول اللہ علیم پیدا ہوتے ہیں اور ادھر دو ماہ
پہلے ابر ہ حملہ کر دیتا ہے.اور اس وقت خدا یہ نشان ظاہر کرتا ہے کہ وہ ابر ہ اور اس کے لشکر کو
تباہ کر دیتا ہے.اتنی مدت تک کسی کو خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کا خیال نہ آنا اور اُس وقت آنا جب
محمد رسول الله علا تعلیم پیدا ہونے والے تھے بتاتا ہے کہ یہ شیطان کی طرف سے اُس وقت آخری
حملہ تھا تا کہ پیشتر اس کے کہ اس انسان کا ظہور ہو جو دعائے ابراہیمی کے ماتحت پیدا ہونے
والا تھا یہ جگہ ہی مٹا دی جائے اور ابراہیمی پیشگوئی کا دنیا میں ظہور نہ ہو.بہر حال اس پیشگوئی کا
پورا ہونا اور ایسے حالات میں پورا ہونا جو بالکل مخالف تھے اور ایسے وقت میں پورا ہونا جب محمد
906
Page 915
رسول اللہ علی پیدا ہونے والے تھے بتاتا ہے کہ اس پیشگوئی کی ایک کڑی اللہ تعالیٰ کے
تصرف میں تھی اور اسی نے مخالف حالات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس عظیم الشان
پیشگوئی کو پورا کیا.دعائے ابراہیمی میں صاف طور پر یہ الفاظ آتے ہیں کہ الہی تو میری اولاد میں
سے ایک ایسا انسان مبعوث کر جو دنیا کو ہدایت دینے والا ہو اور ساتھ ہی یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ
تعالیٰ خانہ کعبہ کو محفوظ رکھے.یہ دونوں دعائیں اللہ تعالیٰ کی کمال حکمت کے ماتحت ایک ہی
وقت میں پوری ہوتی ہیں.محرم میں خانہ کعبہ کو برباد کرنے والا دشمن اٹھتا ہے.اور ربیع الاول
میں وہ شخص پیدا ہو جاتا ہے جو کہتا ہے کہ میں دعائے ابراہیمی کا مصداق ہوں مگر 22 سوسال
تک نہ کسی نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا اور نہ کسی نے یہ کہا کہ میں دعائے ابراہیمی کا مصداق ہوں.کیا یہ سب کچھ اتفاق ہے؟ محمد رسول اللہ صل تعلیم کے دعویٰ کو تم اتفاق کہہ لومگر کیا ابرہہ کے حملہ
کو بھی کوئی اتفاق کہ سکتا ہے؟ یقیناً اگر تعصب سے کام نہ لیا جائے تو نہ محمد رسول اللہ علیم کے
دعوی کو اتفاق کہا جا سکتا ہے اور نہ ابرہہ کے حملہ کو اتفاق کہا جاسکتا ہے.بلکہ تسلیم کرنا پڑتا ہے
کہ یہ جو کچھ ہوا اللہ تعالیٰ کے منشاء اور اس کے ازلی فیصلہ کے مطابق ہوا.پیشگوئی کا پورا ہونا
ناممکن نظر آتا تھا.حالات قطعی طور پر مخالف تھے.اور کوئی انسان محض اپنی عقل سے قیاس کر
کے یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ پیشگوئی پوری ہو جائے گی.مگر ناممکن حالات کو ممکن بناتے ہوئے
اللہ تعالیٰ نے اس پیشگوئی کو پورا کر دیا.اگر اس دنیا میں ایسے نظارے نظر آسکتے ہیں تو کیا اُس
خدا کی بتائی ہوئی وہ پیشگوئیاں پوری نہیں ہوسکتیں جو اگلے جہان سے تعلق رکھتی ہیں.اگر ان
پیشگوئیوں کا پورا ہونا ممکن ہے تو اگلے جہان سے تعلق رکھنے والی پیشگوئیوں کا پورا ہونا کیوں ممکن
نہیں.حمد غرض اللہ تعالیٰ نے هُمَزَۃ اور لُمَزَة کے ساتھ اس سورۃ کو جوڑ کر اس اعتراض کورڈ کیا
ہے جو کفار کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے کہ اگلے جہان کے متعلق جو خبریں دی گئی ہیں وہ ہم
کس طرح مان لیں.اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ دعائے ابراہیمی کونسی ممکن
907
Page 916
تھی.اسماعیل کا موت سے بچ جانا کونساممکن تھا.خانہ کعبہ کا بن جانا اور سارے عرب کی توجہ کا
اس کی طرف پھر جانا کونسا ممکن تھا.28 سوسال کے بعد ایک جرار لشکر کے دل میں خانہ کعبہ
پر حملہ کرنے اور اسے گرا دینے کا احساس پیدا ہونا کونساممکن تھا.اس دشمن
کا تباہ ہونا کونساممکن
تھا اور پھر اس دشمن کی تباہی کے عین دو ماہ بعد اس شخص کا پیدا ہو جانا جس کی خاطر خانہ کعبہ کو
بسایا گیا تھا کونسا ممکن تھا.اگر یہ ساری ناممکن باتیںممکن ہوگئی ہیں تو اگلے جہان کی باتوں پر تم
کیا اعتراض کرتے ہو.جس خدا نے یہ باتیں پوری کی ہیں وہی اگلے جہان کی باتوں کو بھی پورا
کردے گا.غرض قرآن کریم کا یہ طریق ہے کہ وہ اس دنیا کی خبروں اور اگلے جہان کی خبروں کو ملا کر
بیان کرتا ہے.اسی طرح جزا وسزا اور تبشیر وانذار کی خبروں کو بھی ملا کر بیان کرتا ہے تا کہ وہ
قریب الفہم ہو جائیں مثلاً اگلے جہان کی دوزخ اور اگلے جہان کی جنت کی حقیقت انسانی سمجھ میں
نہیں آسکتی جب تک وہ اس جہان سے تعلق رکھنے والی انداری خبروں اور بشارتوں کو پورا
ہوتے نہ دیکھ لے.جب وہ اس جہان سے تعلق رکھنے والی خبروں کو پورا ہوتے دیکھ لیتا ہے تو
اس کے دل میں خود بخود یہ یقین پیدا ہو جاتا ہے کہ جب یہ ناممکن باتیں ممکن ہو گئی ہیں تو اگلے
جہان سے تعلق رکھنے والی خبریں بھی ضروری پوری ہو کر رہیں گی.بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
(میں) اللہ تعالیٰ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا ( اور بار بار رحم رکنے والا ہے
( شروع کرتا ہو ).بسم اللہ کی آیت تمام سورتوں میں مشترک ہے جو ہر سورۃ سے پہلے آتی ہے.میری تحقیق
کے مطابق بسم اللہ مضامین سورۃ کھولنے کی کنجی ہے اور اس میں ایسے گر بتائے گئے ہیں جن
سے اگلی سورۃ کے مضامین خود بخود کھل جاتے ہیں.بڑی چیز جوبسم اللہ کے ذریعہ ظاہر کی گئی
ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی ہر سورۃ میں کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور ہوتی ہے جو غیر معمولی ہوتی
908
Page 917
ہے.مثلاً یا وہ غیر معمولی ہوتی ہے عقیدہ کے لحاظ سے.یعنی دنیا کے عقائد کچھ اور ہوتے ہیں اور
قرآن کریم کوئی اور عقیدہ پیش کرتا ہے جس کی وجہ سے دنیا کہہ دیتی ہے کہ یہ غلط ہے.یا وہ
غیر معمولی ہوتی ہے آئندہ واقعات کے لحاظ سے.یعنی اس میں ایسی پیشگوئی ہوتی ہے جو
حیرت انگیز ہوتی ہے.یا وہ غیر معمولی ہوتی ہے پرانے اخبار کے لحاظ سے.یعنی تاریخ کچھ اور
کہتی ہے مگر قرآن کہتا ہے کہ یہ صحیح نہیں اصل واقعہ یوں ہے.یا غیر معمولی ہوتی ہے اس لحاظ
سے کہ دنیوی قانونِ قدرت جو لوگوں نے سمجھ رکھا ہوتا ہے اس کے خلاف ہوتی ہے اور لوگ
کہتے ہیں کہ قرآن کریم نے یہ بات سائنس کے خلاف کہہ دی ہے.بہر حال کوئی نہ کوئی غیر
معمولی بات اس میں آجاتی ہے.اسی لئے اللہ تعالیٰ نے ہر سورۃ سے پہلے بسم الله الرّحمٰنِ الرَّحِیمِ کو رکھا ہے.یعنی میں
اللہ کا نام لے کر شروع کرتا ہوں جو بغیر کسی محنت اور کوشش کے اور بغیر کسی استحقاق کے
سامان مہیا کرتا ہے.پھر وہ ایسا خدا ہے کہ جب کوئی شخص اس کے پیدا کردہ سامانوں سے کام
لیتا ہے تو وہ اس کی کوشش کا بہتر سے بہتر بدلہ دیتا ہے.جیسے دنیا میں بعض دفعہ بڑے آدمی
کو گواہی کے طور پر پیش کر دیا جاتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر سورۃ سے پہلے اپنے آپ کو
بطور گواہ پیش کیا ہے.ما قرآن کریم میں چونکہ غیر معمولی مطالب آتے ہیں اس لئے ہر سورۃ سے پہلے اللہ تعالیٰ
نے بسم اللہ رکھ دی ہے، یہ بتانے کے لئے کہ تم کہو گے کہ یہ تو غیر معمولی باتیں ہیں ہم کیسے مان
لیں کہ اس طرح ہو کر رہے گا.ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ ان خبروں کا بتانے والا کوئی انسان
نہیں بلکہ ہم جو زمین و آسمان کے مالک ہیں یہ خبر دے رہے ہیں اس لئے ان خبروں کی سچائی
پر تمہیں بہر حال ایمان رکھنا چاہئے.یہی حکمت ہے جس کی بنا پر ہر سورۃ سے پہلے بسم اللہ رکھ دی
گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ تم کو اگر اس میں کوئی غیر معمولی یا ناممکن بات نظر آئے یا آئندہ کے
متعلق کوئی پیشگوئی ہوجس کا پورا ہونا بظاہر مشکل نظر آتا ہو تو تم اس کو غلط مت سمجھو.اس لئے کہ
909
Page 918
وہ خدا کی طرف سے ہے.یہ کتنا بڑا دعویٰ ہے جو قرآن کریم نے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے.دنیا کی اور الہامی کتب میں سے ہر کتاب الہی ہونے کا تو دعوی کرتی ہے مگر وہ کتاب کے ہر
ٹکڑے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرار نہیں دیتی.عیسائی خود اپنے ہاتھ سے لکھتا ہے کہ انجیل
میں فلاں فلاں بات غلط ہے اور پھر کہتا ہے کہ انجیل خدا کی کتاب ہے.اور جب اس سے
پوچھا جائے کہ یہ کیا.ایک طرف تو تم انجیل کی بعض باتوں کو غلط قرار دیتے ہو اور دوسری
طرف اسے الہی کتاب کہتے ہو؟ تو وہ جواب دیتا ہے کہ انجیل صرف اپنی مجموعی حیثیت میں خدا
کی کتاب ہے.یہ نہیں کہ اس کا ہر لکڑہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے.اسی طرح یہودی اپنے
ہاتھ سے لکھتا ہے کہ بائبل کی فلاں فلاں بات غلط ہے اور پھر ساتھ ہی یہ بھی کہتا ہے کہ بائبل خدا
کی کتاب ہے.اور جب اُس سے پوچھا جائے کہ وہ کیوں ایسا متضاد دعوی کرتا ہے تو وہ کہتا
ہے کہ بائبل بحیثیت مجموعی خدا کی طرف سے ہے.یہ نہیں کہ اس کا ہر ٹکڑہ اللہ تعالی نے نازل
کیا ہے.اس کے مقابلہ میں قرآن کریم کی یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اس نے ہر ٹکڑے سے
پہلے بسم اللہ نازل کر کے یہ دعویٰ پیش کیا ہے کہ اس کا ہر ٹکڑہ میری طرف سے ہے.یہ بھی
میری طرف سے ہے اور وہ بھی میری طرف سے ہے.تا کوئی شخص بائبل یا انجیل کی طرح یہ نہ
کہہ سکے کہ فلاں ٹکڑہ خدا کی طرف سے نہیں بلکہ نعوذ باللہ انسانوں نے اس میں ملا دیا ہے.گو یا بسم اللہ نے قرآن کریم کے ہر ٹکڑے پر مہر لگادی ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی طرف
سے ہے اور یہ کہ اگر کوئی ایک ٹکڑہ بھی غلط نکلے تو یہ کتاب خدا کی طرف سے نہیں ہو سکتی.بائبل
پر ایمان رکھنے والا کہ دیتا ہے کہ بائبل کا جو حصہ پورا ہورہا ہے یہ خدا کی طرف سے ہے اور جو
حصہ پورا نہیں ہورہا یہ انسانوں کی طرف سے ہے.مگر قرآن کہتا ہے کہ اگر اس کتاب کا کوئی
ایک ٹکڑہ بھی پورا نہیں ہوتا تو تم سمجھ لو کہ ساری کی ساری کتاب خدا کی طرف سے نہیں.غرض
بسم اللہ نے قرآن کریم کے ہر ٹکڑے کی ذمہ واری اللہ تعالیٰ پر ڈال دی ہے اور بار بار وہ اس
ذمہ داری کا اظہار کرتا ہے.بے شک بائبل بھی خدا تعالیٰ کی کتاب ہے مگر اس کے باوجود
910
Page 919
بائبل کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس میں ایسے حصے ہیں جو انسانوں نے اپنے ہاتھ سے اس میں ملا
دیتے ہیں.اسی طرح انجیل کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ خدا کی طرف سے ہے مگر اس کے باوجود
اس میں ایسے ٹکڑے بھی ہیں جن کے متعلق عیسائی کہتے ہیں کہ وہ خدا کی طرف سے نہیں.یہی
مشکل قرآن کریم کے متعلق بھی پیش آسکتی تھی.اگر ایک دفعہ ہی قرآن کریم میں بسم اللہ آتی تو
ہوسکتا تھا کہ بعض مسلمان اپنی بے ایمانی میں یہ کہہ دیتے کہ فلاں ٹکڑہ خدا کی طرف سے نہیں
بعض انسانوں نے اس میں ملا دیا ہے.اس نقص کے ازالہ کے لئے اللہ تعالیٰ نے ہر ٹکڑہ سے
پہلے بسم اللہ نازل کر دی ہے اور اس طرح بتایا ہے کہ قرآن کریم سارے کا سارا اللہ تعالیٰ کی
طرف سے ہے.بائبل کی اگر ایک آیت غلط ثابت ہو جائے تو یہودی یہ نہیں مانے گا کہ
ساری بائبل غلط ہے.انجیل کی اگر ایک آیت غلط ثابت ہو جائے تو عیسائی یہ نہیں مانے گا کہ
ساری انجیل غلط ہے.لیکن قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ ہم دنیا کے سامنے یہ دعویٰ پیش کرتے ہیں
کہ اس کا ایک ایک ٹکڑہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے.اس کی چھوٹی سے چھوٹی سورۃ بھی اللہ
تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اس کی بڑی سے بڑی سورۃ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے.اگر
کوئی ایک ٹکڑہ بھی غلط ثابت ہو جائے تو سمجھ لو کہ سارا قرآن غلط ہے خدا نے اسے نازل
نہیں کیا.یہ کتنا عظیم الشان دعوی ہے جو قرآن کریم نے پیش کیا ہے.اس کے مقابلہ میں دنیا
کی کوئی الہامی کتاب نہیں ٹھہر سکتی.دنیا میں لوگ اپنی ذمہ داریاں کم کیا کرتے ہیں مگر قرآن
کریم نے بار بار بسم اللہ نازل کر کے اپنی ذمہ داریوں کو بہت بڑھا لیا ہے.اگر ایک دفعہ
بسم اللہ آتی تو خیال کیا جا سکتا تھا کہ کچھ ٹکڑے ایسے بھی ہوں جو خدا تعالیٰ کی طرف سے نہ
ہوں.مگر ہر سورۃ سے پہلے بسم اللہ نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ کوئی ٹکڑہ بھی ایسا
نہیں جس کی صداقت کی ذمہ داری ہم نہ لیتے ہوں.اس لئے کسی ایک ٹکڑے کا غلط ہونا
در حقیقت سارے قرآن کا غلط ہونا ہے.مگر کوئی ایک ٹکڑہ بھی ایسا ثابت نہیں کیا جا سکتا جو غلط
ہو اور جس کی صداقت دنیا پر واضح نہ کی جاسکتی ہو.غرض یہ آیت قرآن کریم کے مشترک مضامین
911
Page 920
کی کنجی اور اس کے ہر ٹکڑہ کے خدا کی طرف سے نازل ہونے کی ایک بین دلیل ہے.بسم الله الرّحمنِ الرَّحِيمِ میں اسلامی عقیدہ کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے.اسلامی
عقیدہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی اس دنیا میں ہے وہ خدا کا ہے اور جو کچھ ہورہا ہے خدا کرتا ہے.کوئی
چیز خدا تعالیٰ کے اختیار سے باہر نہیں اور کسی بات میں خدا تعالیٰ کسی دوسرے کی امداد کا محتاج
نہیں.ہر چیز جو ماسوی اللہ ہے وہ خدا تعالیٰ کی محتاج ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر وہ کچھ
نہیں کرسکتی.اسی کو عربی زبان میں تو گل کہتے ہیں.یعنی اس عقیدہ کے مطابق انسانی عمل کا نام
اسلامی اصطلاح میں تو کل ہے.پس بسم اللہ الرحمن الرحیم میں توکل علی اللہ کی تفسیر بیان کی گئی
ہے.اس کے معنے یہ ہیں کہ ہم خدا سے مدد مانگتے ہوئے ،ایسے خدا سے مدد مانگتے ہوئے جس
نے سب کے سب سامان بغیر کسی محنت اور کوشش اور تدبیر کے مہیا کر کے دیتے ہیں اور جو
ان سامانوں سے کام لینے پر پھر اچھے سے اچھا اور ہمیشہ اور بار بار نتیجہ خیز بدلہ دیتا ہے اس کام
کو شروع کرتے ہیں.یہ مختصراً ترجمہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا.اور حقیقت یہ ہے کہ اگر اس
کی تفسیر کی جائے تو اسی پر کئی کتابیں لکھی جاسکتی ہیں.گویا اس چھوٹی سی آیت میں یہ پیش کیا گیا
ہے کہ حال خدا تعالیٰ کے اختیار میں ہے.کیونکہ جب انسان کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم.میں خدا سے مدد مانگتا ہوں.تو اس کے معنے یہ ہوتے ہیں کہ یہ زمانہ جس میں میں ہوں اور کام
کرنا چاہتا ہوں خدا تعالیٰ کے اختیار میں ہے.اگر حال خدا تعالیٰ کے اختیار میں نہیں تو وہ مدد
کس سے مانگتا ہے.مدد اسی سے مانگی جاتی ہے جس کے قبضہ و تصرف میں حال کا زمانہ ہو.پس اگر میں کام کرتے ہوئے خدا تعالیٰ سے مدد مانگتا ہوں تو درحقیقت میں اس بات کا اقرار
کرتا ہوں کہ موجودہ زمانہ میں خدا تعالیٰ کو طاقت حاصل ہے.پھر الرحمن کا لفظ آتا ہے.یعنی میں اس سے مدد مانگتا ہوں جو رحمن ہے.رحمن کے معنے ہیں بغیر کوشش محنت اور خدمت
کے ہر قسم کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا.گویا رحمانیت کے ماتحت وہ تمام چیزیں شامل ہیں جو
غیر کسی محنت اور کوشش کے انسانوں کو ملتی ہیں.رحمانیت میں آسمان کی پیدائش بھی شامل
912
Page 921
ہے رحمانیت میں زمین کی پیدائش بھی شامل ہے.رحمانیت میں پانی بھی شامل ہے.رحمانیت
میں ہوا بھی شامل ہے.رحمانیت میں انسان کا اپنا جسم بھی شامل ہے.رحمانیت میں اس کے
تمام قومی مثلاً ناک کان اور آنکھیں وغیرہ بھی شامل ہیں.رحمانیت میں حیوانات بھی شامل ہیں.رحمانیت میں جمادات بھی شامل ہیں.رحمانیت میں چاند اور ستارے وغیرہ بھی شامل ہیں.غرض جو کچھ بھی اس دنیا میں پایا جاتا ہے جس کے بنانے میں ہم نے محنت نہیں کی وہ رحمانیت کا
نتیجہ ہے اور ہر چیز جس کے بنانے میں ہم نے ہاتھ ہلایا ہے وہ رحیمیت ہے.دنیا میں دو ہی
چیزیں ہیں.یا تو ایسی چیزیں ہیں جن کے بنانے میں انسان نے حصہ نہیں لیا.یا ایسی
چیزیں ہیں جن کے بنانے میں انسان نے حصہ لیا ہے.وہ چیزیں جن کے بنانے میں انسان
نے حصہ نہیں لیا وہ رحمانیت کی صفت کے ماتحت آتی ہیں.ان کے لئے کیوں رحمانیت کا لفظ
بولا گیا ہے؟ کیوں نہیں کہا گیا کہ کچھ چیزیں خدا نے بنائی ہیں اور کچھ ایسی ہیں جن میں
بندوں کی محنت اور ان کی کوشش کا دخل ہے.کیوں خدا نے یہ نہیں کہا اور لفظ رحمن سے اس
مفہوم کو ادا کیا ہے.اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ لفظ بولے جاتے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو
خدا نے پیدا کی ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بندوں نے بنائی ہیں تو ان الفاظ سے یہ نتیجہ تو نکلتا
کہ ان پیدا کی ہوئی اشیاء میں سے کچھ چیزیں خدا کی بھی ہیں مگر یہ نتیجہ نہ نکلتا کہ جو چیزیں خدا نے
پیدا کی ہیں وہ سب کی سب انسان کے فائدہ کے لئے پیدا کی گئی ہیں.یہ سوال بہر حال باقی رہ
جاتا کہ وہ چیزیں جو خدا نے بنائی ہیں وہ کسی فائدہ کے لئے ہیں یا ان میں سے کچھ بے فائدہ بھی
ہیں.مگر رحمانیت کے لفظ نے بتا دیا کہ وہ سب کی سب ہمارے فائدہ کے لئے ہیں.رحم کا لفظ
کسی کو فائدہ پہنچانے کے لئے بولا جاتا ہے.یونہی نہیں بولا جاتا.مثلاً اگر سورج چمک رہا ہو تو
ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بڑا رحم کر رہا ہے.کیونکہ رحم میں دو باتوں
کا پایا جانا ضروری ہوتا ہے.اول دوسرے کے فائدہ کا کام کرنا.دوم اس نیت سے کرنا کہ دوسرے کو فائدہ پہنچے.فرض کرو
کوئی شخص جا رہا ہے اور اس کی جیب سے اتفاقاً ایک پیسہ گر گیا ہے.کسی اور نے اٹھالیا
913
Page 922
ہے.اب اسے فائدہ تو پہنچ گیا مگر کیا کوئی شخص اس وجہ سے کہ اس کے پیسہ سے دوسرے
نے فائدہ اٹھا لیا ہے یہ کہے گا کہ وہ بڑے رحم کرنے والے انسان ہیں.پس رحم کے معنوں میں
صرف یہی بات شامل نہیں ہوتی کہ دوسرے کو فائدہ پہنچے بلکہ اس میں یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ
دوسرے کو فائدہ پہنچانے کی نیت بھی ہو.پس رحمن کا لفظ بول کر بعض زائد امور بیان کئے گئے
ہیں جو اس لفظ کے بغیر ادا نہیں ہو سکتے تھے.یعنی یہی نہیں کہا گیا کہ خدا نے ایسی چیزیں پیدا
کی ہیں جن کے پیدا کرنے میں انسان کا دخل نہیں.بلکہ خدا نے ان چیزوں کو پیدا ہی انسان
کے فائدہ کے لئے کیا ہے اور اس نیت سے پیدا کیا ہے کہ انسان ان سے فائدہ اٹھائے.رحِیم فعیل کے وزن پر ہے اور یہ وزن تو اتر اور لمبے زمانہ کی طرف اشارہ کرتا ہے اور رحمن
فعلان کے وزن پر ہے اور وسعت کی طرف اشارہ کرتا ہے.رحیم کے معنے ہیں وہ جو بار بار نتائج پیدا کرتا ہے.جب رحمانیت کے سامانوں سے
انسان فائدہ اٹھالیتا ہے تو رحیم خدا اس کے بار بار نتائج پیدا کرتا ہے.مثلاً انسان روٹی کھاتا
ہے روٹی کھانے کا یہی نتیجہ نہیں ہوتا کہ پیٹ بھر جاتا ہے بلکہ اس کے نتیجہ میں خون پیدا ہوتا
ہے جو مہینوں اور سالوں انسانی جسم میں کام کرتا ہے.اسی خون سے اس کے دماغ کو طاقت ملتی
ہے اس کی نظر کو طاقت ملتی ہے.اس کے ذہن کو طاقت ملتی ہے.اس کے کانوں کو طاقت
ملتی ہے جو مہینوں اور سالوں اس کے کام آتی ہے.پھر اسی میں سے نطفہ پیدا ہوتا ہے جس سے
اس کی نسل پیدا ہوتی ہے.پھر اس نسل سے اگلی نسل اور اگلی نسل سے اور اگلی نسل پیدا ہوتی
ہے.گویا ایک ایک فعل تواتر سے نتائج پیدا کرتا ہے.یہ رحیمیت ہے.اگر دنیا میں صرف
یہی سلسلہ ہوتا کہ جب کوئی شخص کام کرتا تو اسی وقت اس کا ایک نتیجہ پیدا ہوجاتا تو ہم اس کو بدلہ
تو کہہ سکتے تھے جیسے مزدور مزدوری کرتا ہے تو اپنی اجرت لے لیتا ہے مگر ہم اسے رحیمیت
نہیں کہہ سکتے تھے.رحیمیت کی مثال ایسی ہی ہے جیسے پنشن ہوتی ہے.لوگ ملازمت
کرتے ہیں تو انہیں اس کا بھی ایک بدلہ مل رہا ہوتا تھا.مگر اس کے ساتھ ہی ان کے کھاتے
914
Page 923
میں یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ آئندہ اس کام کا متواتر نتیجہ پیدا ہوگا.چنانچہ اگر کوئی دس یا پندرہ سال
ملازمت کرتا ہے تو وہ تنخواہ کے 1/10 حصہ کی پنشن کا حقدار ہو جاتا ہے.بیس سال گزر
جائیں تو 3 / 1 پنشن کا حقدار ہو جاتا ہے.پچیس سال گزر جائیں اور وہ ڈاکٹری سارٹیفیکیٹ
بھی پیش کر دے تو اسے نصف پنشن مل جاتی ہے اور اگر تیس سال گزر جائیں تو بغیر ڈاکٹر
سارٹیفکیٹ کے ہی وہ پوری پنشن کا حقدار بن جاتا ہے.یہ چیز ہے جو رحیمیت کے مشابہ ہے
یعنی کام کا بدلہ نقد ہی نہیں ملا بلکہ آئندہ کے لئے اور نیک نتائج کی بنیاد بھی ساتھ ہی رکھ دی گئی.پھر یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان کی رحیمیت اور خدا تعالیٰ کی رحیمیت میں
فرق کیا ہے؟
اس کا جواب یہ ہے کہ جب انسان بدلہ دیتا ہے تو یہ مجھ کردیتا ہے کہ اس شخص نے کچھ
سالوں کے بعد مر جانا ہے اگر اسے پتہ لگ جائے کہ اس شخص نے کبھی نہیں مرنا تو وہ کبھی اسے
پنشن نہ دے.مگر چونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ اس نے ضرور چند سالوں کے اندر اندر مر جانا ہے
اس لئے وہ پنشن دے دیتا ہے.لیکن خدا کو نہ صرف یہ پتہ ہے کہ انسان نہیں مرے گا بلکہ وہ خود
کہتا ہے کہ میں انسان کو ماروں گا نہیں بلکہ اسے ابدی زندگی دوں گا.گویا یہی نہیں کہ وہ اتفاقی
طور پر اس حادثہ کو برداشت کر لیتا ہے بلکہ وہ انسان کے زندہ رہنے اور اس کی دائمی حیات کے
خود سامان مہیا کرتا ہے.اس لئے خدا کی رحیمیت کی شان اور ہے اور انسان کی رحیمیت کی
شان اور ہے.بہر حال بسم اللہ حال پر رحمن ماضی پر اور رحیم کا لفظ مستقبل پر دلالت کرتا ہے اور یہ
تینوں الفاظ بتاتے ہیں کہ تمام کے تمام کاموں میں تقدیر الہی انسان کے ساتھ وابستہ ہے.بسم اللہ میں چھوٹی سی تدبیر شامل ہے.یعنی انسان کہتا ہے میں خدائی مدد سے یہ کام شروع کرتا
ہوں.گویا ارادہ انسان کا اپنا ہوتا ہے.اگر میرا ارادہ کسی کام کے متعلق نہ ہو تو میں یہ کس
طرح کہہ سکتا ہوں کہ میں خدا کی مدد سے فلاں کام شروع کرتا ہوں.بہر حال اس میں کچھ
915
Page 924
بندے کا بھی دخل ہوتا ہے.اس کے بعد رحمانیت کا دائرہ ہے جو خالص خدا سے تعلق رکھتا
ہے.اور رحیمیت میں تھوڑا سا کام بندہ کرتا ہے اور غیر منتہی نتیجہ خدا پیدا کرتا ہے.گویا تدبیر اور
تقدیر دونوں سے مل کر یہ دنیا چلتی ہے.اور بسم اللہ ہم کو بتاتی ہے کہ تقدیر اور تدبیر آپس میں
اس طرح الجھی ہوئی ہیں کہ ان کو الگ الگ نہیں کیا جا سکتا.آگے انسان کی مختلف حیثیتوں
کے لحاظ سے اس کے کام بڑے اور چھوٹے ہوتے چلے جاتے ہیں.ایمان کامل میں تقدیر کا
پہلو غالب ہوتا ہے اور تدبیر کا پہلو کمزور ہوتا ہے جیسے رحمانیت خالص خدا کی تھی.اسی طرح جو
انسان خدا تعالیٰ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے اس کی زندگی کے کاموں میں بھی تقدیر زیادہ اور
تدبیر کم نظر آتی ہے.وہ بیشک تدبیر بھی کرتا ہے مگر اس کے نتائج اس کی تدبیر سے بہت زیادہ
پیدا ہوتے ہیں.حمد حضرت خلیفہ اول رضی اللہ عنہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ دہریہ سے دہریہ بھی خدا تعالیٰ
کی تقدیر سے باہر نہیں ہوتا.ایک دہریہ کی زبان پر بھی میٹھارکھ دو تو باوجود اس کے کہ وہ خدا کو
گالیاں دیتا ہوگا مگر خدا کو گالیاں دینے والی زبان بھی اس میٹھے کو میٹھا ہی چکھے گی.غرض تقدیر ہر
ایک شخص کے کام کے ساتھ کام کر رہی ہوتی ہے مگر تد بیر کا پہلو غالب ہوتا ہے اور تقدیر کا پہلو
کمزور ہوتا ہے سوائے اہل اللہ کے کہ ان کا حساب اس کے الٹ ہوتا ہے.ان دو کے علاوہ جو
در میانی درجہ کا مومن ہوتا ہے خواہ وہ کلامِ الہی کو ماننے والا ہو یا نہ ماننے والا ہو جیسے عیسائی کہ وہ
بھی اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں کیونکہ وہ عیسائی مذہب کو تسلیم کرتے ہیں حالانکہ وہ اسلام پر
ایمان نہیں لائے.اسی طرح یہودی بھی اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں کیونکہ وہ یہودی مذہب کو
تسلیم کرتے ہیں.ہندو بھی اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں کیونکہ وہ ہندو مذہب کو تسلیم کرتے
ہیں.ان لوگوں کے لئے خواہ وہ کلام الہی کو ماننے والے ہوں یا نہ ہوں دونوں چیزوں کا امتزاج
ہوتا ہے اور تقدیر اور تدبیر ان کے لئے ملی ہوئی ہوتی ہیں.ایسے لوگ دعائیں بھی کرتے
ہیں خواہ وہ سچے مذہب پر نہ ہوں جیسے عیسائی اور یہودی اور ہند وسب دعاؤں سے کام لیتے ہیں
916
Page 925
اور تدبیر سے بھی کام لیتے ہیں.گویا تقدیر اور تدبیر کا ایک لطیف امتزاج ان دونوں کے لئے
ہوتا ہے.غرض مومن کامل جو خدا تعالیٰ کے رنگ میں رنگین ہو جاتا ہے اس کے کاموں میں
تقدیر کا پہلو غالب ہوتا ہے.اور جو شخص خدا تعالیٰ سے دُور چلا جاتا ہے اس کے کاموں میں
تدبیر کا پہلو غالب ہوتا ہے اور جو درمیانی درجہ کا آدمی ہوتا ہے اس کے کاموں میں تقدیر اور
تدبیر دونوں ملی ہوئی ہوتی ہیں.یہ مضمون ہے جس کو بسم اللہ ظاہر کرتی ہے اور چونکہ ہر سورۃ سے پہلے بسم اللہ آتی ہے.اس
لئے جب انسان بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو وہ اس امر کا اقرار کرتا ہے کہ جو کچھ آگے
مضمون بیان ہو رہا ہے اس سے میں اپنے ایمان اور عرفان کے لحاظ سے فائدہ اٹھانے کی
کوشش کروں گا.اگر وہ اعلیٰ درجے کا ایمان رکھنے والا ہے تو وہ اس سے ایسا فائدہ اٹھاتا ہے
کہ وہ سورۃ اس کے لئے ویسی ہی بن جاتی ہے جیسے محمد رسول اللہ علی تعلیم کے لئے نازل ہوئی
تھی.اور اگر وہ دشمنی کرتا ہے تو کچھ بھی فائدہ نہیں اٹھاتا.ساری کی ساری سورۃ بیکار اور رائیگاں
چلی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر اس کے حق میں ضائع ہو جاتی ہے.اور اگر وہ درمیانی درجہ کا
مومن ہو تو سورۃ کا مضمون صرف ایک حد تک اسے فائدہ بخشتا ہے، پورا فائدہ نہیں دیتا.الَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحُبِ الْفِيْلِ
(اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ) کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے ربّ نے ہاتھی (استعمال
کرنے ) والوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا.الم تر اصل میں الم تری ہے.آخر جب فعل مضارع پر آتا ہے تو اگر اس کے
آخر میں یاء ہو تو وہ گر جاتی ہے.اسی وجہ سے الخ تری کی بجائے صرف آلخ تر رہ گیا.اس کے
معنے یہ ہیں کہ کیا تو نے دیکھا نہیں.یہاں دیکھنے سے دل کی آنکھوں سے دیکھنا اور بصیرت کی راہ سے دیکھنا مراد ہے.آنکھوں
سے دیکھنا مراد نہیں ہو سکتا.کیونکہ جس واقعہ کی طرف یہاں اشارہ کیا گیا ہے وہ
917
Page 926
رسول کریم علیم کی پیدائش سے پہلے کا ہے.کتنا پہلے کا ہے؟ اس بارہ میں اختلاف ہے....صحیح روایت جس کے قرائن بعض دوسری تاریخوں سے بھی ملتے ہیں یہ ہے کہ در حقیقت یہ اسی
سال کا واقعہ ہے جس سال میں رسول کریم عالم پیدا ہوئے تھے.جو تاریخی شہادتیں کثرت
سے مل جاتی ہیں اور جن کے قرائن دوسری تاریخوں یا دوسرے ملکوں کی تاریخوں سے بھی
ملتے ہیں وہ اسی کی تائید کرتی ہیں.یہ واقعہ محرم میں ہوا تھا جو اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور
رسول کریم علیم کی پیدائش اسی سال ربیع الاول میں ہوئی ہے.پس جبکہ رسول کریم علیم کی پیدائش سے یہ واقعہ پہلے ہوا ہے خواہ تیس دن پہلے ہوا ہو خواہ
تیس سال بہر حال رسول کریم یا لیلی نے یہ واقعہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا.اس لئے ترسے
رؤیت قلبی ہی مراد لی جائے گی.رؤیت عینی نہیں.پس آلخ تر کے لفظی معنے یہ ہوئے کہ کیا
تجھے معلوم نہیں.اس فقرہ کے عام طور پر دو معنے ہو سکتے ہیں.اوّل یہ کہ ہم دوسرے شخص سے
پوچھتے ہیں کہ آیا فلاں بات اسے معلوم ہے یا نہیں؟ دوسرے معنے اس قسم کے فقرہ کے یہ
ہوتے ہیں کہ تمہیں یہ بات خوب معلوم ہے.گویا بظاہر نفی کے الفاظ ہوتے ہیں مگر معنے مثبت
ہی کے ہیں بلکہ مثبت پر زور دینے کے ہوتے ہیں.اردو میں بھی کہتے ہیں تمہیں معلوم نہیں میں
ایسا کرسکتا ہوں.اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں ایسا کرنے کی
طاقت رکھتا ہوں.گویا اس قسم کا فقرہ بجائے اس کے کہ شک کا اظہار کرے یقین اور وثوق پر
دلالت کرتا ہے.اگر ایسا فقرہ کہنے والا کوئی انسان ہو تو کسی کو شبہ بھی ہوسکتا ہے کہ آیا اس نے
شک کے معنوں میں استعمال کیا ہے یا وثوق کے معنوں میں.لیکن خدا تعالیٰ کے متعلق ہم یہ
نہیں خیال کر سکتے کہ نعوذ باللہ اس کے قول کا یہ مطلب ہے کہ مجھے تو معلوم نہیں کہ تم کو فلاں
واقعہ کا علم ہے یا نہیں.تم ہی بتاؤ کہ تمہیں اس کا علم ہے یا نہیں.پس یہ فقرہ شک کے معنوں
میں خدا تعالیٰ کے متعلق استعمال ہی نہیں ہو سکتا.کیونکہ قرآن کریم کہتا ہے کہ اس سے کوئی چیز
مخفی نہیں اور جب وہ کہتا ہے کہ خدا تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی نہیں تو اس کی طرف وہ معنے کبھی
918
Page 927
منسوب نہیں ہو سکتے جن میں شک وشبہ پایا جاتا ہو.پس اس آیت کے وہی معنے مراد لینے ہوں
گے جو یقین اور قطعیت پر دلالت کرتے ہیں.پس آلغر تر کے لفظی معنے گو یہی ہیں کہ کیا تمہیں معلوم نہیں.مگر در حقیقت اس کا مفہوم اس
جگہ یہ ہے کہ تم خوب اچھی طرح سے جانتے بوجھتے اور سمجھتے ہو اور تم سے یہ حقیقت مخفی نہیں ہے.الم تر کے متعلق ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی مخاطب تو ساری دنیا
ہے.آیا الخمر تر میں بھی ساری دنیا مخاطب ہے یا محمد رسول الله علیم مخاطب ہیں یا دشمنانِ
اسلام مخاطب ہیں؟
اس کا جواب یہ ہے کہ یوں تو قرآن کریم ساری دنیا کے لئے ہے خواہ بعض آیات میں
براه راست محمد رسول اللہ العلیم ہی کیوں نہ مخاطب ہوں.مگر اس سورۃ کے الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے کہ
یہاں خطاب براہ راست محمد رسول اللہ علیم کی ذات سے ہے اور پھر آپ کے توسط سے باقی دنیا
مخاطب ہے.چنانچہ آگے ہی فرماتا ہے.كَيْفَ فَعَل ربك تیرے رب نے کس طرح کیا.یوں
تو خدا تعالیٰ سب کا رب ہے مگر جب ایک ایسے واقعہ کا ذکر کیا گیا ہے جو عرب اور خصوصا رسول کریم
لامی کی زندگی سے تعلق رکھتا ہے تو ربک کے الفاظ سے یہی سمجھا جائے گا کہ اس میں خطاب
خصوصیت سے رسول کریم علیم کی ذات اقدس سے ہی کیا گیا ہے.غرض اس آیت میں ت اور ک یہ دوضمائر خطاب کی ہیں.پس تر اور رتبہ یہ دو الفاظ جو اس
جگہ آئے ہیں بتاتے ہیں کہ اس واقعہ کا تعلق خصوصیت سے رسول کریم معلم کے ساتھ ہے
اور اس سورۃ میں جو مضمون بیان ہوا ہے اس کا اصل اور اہم تعلق محمد رسول اللہ علیم سے ہی
ہے.اگر محمد رسول اللہ علی ایم کی ذات سے اس کا خاص تعلق نہ ہوتا تو ربك کہنے کی کیا
ضرورت تھی.جب خدا نے کہا کہ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ - تیرے خدا نے اس سے کس طرح کا سلوک
کیا.تو اس کے معنے در حقیقت یہی ہیں کہ ہم نے اس وقت جو کچھ کیا تھا محض تیرے لئے کیا
919
Page 928
تھا.ورنہ اگر یہ مفہوم نہ لیا جائے تو اصحاب الفیل کے واقعہ کا علم رکھنے میں محمد رسول اللہ علیم
کی کیا خصوصیت ہے.عرب کا بچہ بچہ جانتا تھا کہ ایسا واقعہ ہوا ہے بلکہ خود رسول کریم حالا ایلیم
کے وقت تک ایسے لوگ موجود تھے جنہوں نے اصحاب الفیل کا واقعہ دیکھا تھا.ایسی صورت
میں الغر تر کہنے کے کوئی معنے ہی نہیں بنتے.وہ واقعہ جو اور ہزاروں لوگوں کو معلوم تھا اور جس
کو دیکھنے والے بھی کئی زندہ موجود تھے.اسی واقعہ کا اگر رسول کریم بیا یہ کوبھی علم ہو گیا تو اس
میں آپ کی خصوصیت کیا رہی؟ آپ کی خصوصیت اسی صورت میں ظاہر ہوتی ہے کہ اس واقعہ کا
آپ سے کوئی خاص تعلق ہو.پھر اس آیت میں اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ کے الفاظ ہیں.یعنی تیرے رب نے کس
طرح کیا.یہ نہیں فرمایا کہ آلَمْ تَرَ مَا فَعَلَ رَبُّكَ تجھے معلوم نہیں کہ تیرے رب نے کیا کیا.کس طرح کیا اور کیا کیا، میں بہت بڑا فرق ہے.اگر صرف یہ بیان کرنا مقصود ہوتا کہ اللہ
تعالیٰ نے اصحاب الفیل سے کیا کیا تو کیف کا لفظ اللہ تعالیٰ اس جگہ استعمال نہ کرتا.مگر اس نے
کیف کا لفظ استعمال کیا ہے جو بتاتا ہے کہ یہاں یہ بیان کرنا مقصود نہیں کہ اصحاب الفیل سے
کیا ہوا.بلکہ یہ بتانا مقصود ہے کہ اصحاب الفیل سے جو کچھ ہوا کس طرح ہوا.عربی زبان کی یہ
خصوصیت ہے کہ اس میں تھوڑے سے فرق کے ساتھ کلام کے مفہوم میں بہت بڑی تبدیلی پیدا
ہو جاتی ہے.کیف کے لفظ نے مضمون کو ایسی خوبی بخش دی ہے جو اس کی شان کو بہت بڑھا دیتی
ہے.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَل ربك تمہیں معلوم ہے کہ ان سے کس
طرح کیا.یہاں کمیت پر زور دینا مقصود نہیں.یہ مراد نہیں کہ دس مرے تھے یا سو.ہاتھی مرے
تھے یا کتے.افسر مرے تھے یا ما تحت.بلکہ ان غیر معمولی حالات کی طرف اشارہ مقصود ہے جن
میں ان کی ہلاکت واقعہ ہوئی.خواہ ایک ہی شخص مرا ہو مگر وہ مرا اس طرح کہ دنیا کہتی تھی کہ وہ
نہیں مرے گا مگر پھر بھی وہ مر گیا.پس یہاں کمیت کا بتانا مقصود نہیں بلکہ کیفیت کا بتانا مقصود
920
Page 929
ہے.یعنی غیر معمولی حالات اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدا کر دئیے گئے.جن حالات کو انسانی
عقل سمجھ ہی نہیں سکتی تھی.مگر مفسرین کا بڑا زور اس امر پر ہوتا ہے کہ ان کے سر پر پتھر پڑے
اور پاخانہ کی جگہ سے نکل گئے.یا یہ کہ ان میں سے کوئی ایک بھی بیچ کر واپس نہ جا سکا.حالانکہ
قرآن اس پر زور ہی نہیں دے رہا.قرآن تو کہتا ہے کہ اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ کیا تم نے
دیکھا اور غور کیا کہ تمہارے رب نے کیسے غیر معمولی حالات میں اصحاب الفیل کو تباہ کیا.خدا تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ان میں بڑی موت واقعہ ہوئی.بڑی موت تو بعض دفعہ جہاز کے
ڈوبنے سے بھی ہو جاتی ہے.خدا تعالیٰ جس امر پر زور دینا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ تم میرا ہاتھ دیکھو
اور اس امر پر غور کرو کہ جو کچھ کیا تھا میں نے کیا تھا.کسی انسانی ہاتھ کا اس میں دخل نہیں تھا.پس حقیقت اور واقعات پر زور دینا اس جگہ مطلوب نہیں بلکہ اس کے نادر اور مخفی الاسباب
ہونے پر زور دینا مقصود ہے.یہ سوال نہیں کہ ابرہہ اور اس کا لشکر سب کا سب مر گئے یا کچھ بیچ
بھی گئے.بلکہ سوال یہ ہے کہ وہ کس طرح مرے.جو بھی مرے ان کے مرنے میں کسی انسانی
تدبیر کا دخل نہیں تھا بلکہ محض ہمارے پیدا کردہ حالات کے نتیجہ میں وہ بلاک ہوا.پس یہاں خدا
اپنے فعل کو پیش کر رہا ہے.وہ یہ نہیں بتا تا کہ ابرہہ پر کیسی تباہی آئی.بلکہ یہ بتاتا ہے کہ اس
پر کیسے تباہی آئی.وہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے ابرہہ کو ان حالات میں مارا جبکہ دنیا اس کے مارے
جانے کا خیال بھی نہ کر سکتی تھی.پس خدا تعالیٰ اس جگہ اپنے فعل پر زور دے رہا ہے اور اس پر
زور دے رہا ہے کہ اس نے یہ فعل محض محمد رسول اللہ علیم کی خاطر کیا.پس اس صورت میں محمد رسول اللہ علیم کے احترام کا اور محمد رسول اللہ علیم کی خاطر اپنی
قدرت دکھانے کا اور محمد رسول اللہ عالم کی ذات کو دشمن کے حملہ سے بچانے کا خصوصیت
سے ذکر کیا گیا ہے.خانہ کعبہ کی حفاظت یا اس کا بچنا ایک ضمنی چیز ہے.خانہ کعبہ کی حفاظت اصل مقصود نہیں تھی بلکہ اصل مقصود محمد رسول الله علی شمیم کی حفاظت
تھی.چنانچہ فرماتا ہے اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ تو نے دیکھا تیرے رب نے کس طرح معاملہ
921
Page 930
کیا.اس میں رتبہ کا لفظ صاف طور پر بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا منشاء یہ ہے کہ اس واقعہ سے
خانہ کعبہ کو بچانا اتنا مطلوب نہ تھا جتنا تیری ذات کو بچانا مقصود تھا.اس آیت میں ایک طرف كَيْفَ فَعَل کہہ کر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اس میں کسی
بندے کا ہاتھ نہیں تھا.پھر ربك کہہ کر یہ بتایا ہے کہ ہم نے یہ نشان کس کے لئے ظاہر کیا تھا.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے.اے محمد رسول اللہ علی ملایم بیشک مکہ والوں کی بھی خاطر ہو گئی.بیشک
خانہ کعبہ کا بھی اعزاز ہو گیا.مگر یہ ایک ضمنی بات تھی.اے محمد رسول اللہ علیم ہم نے تو یہ نشان
محض تیرے لئے دکھایا تھا اور تو ہی ہمارا اصل مقصود تھا.پس درحقیقت یہ نشان محمد
رسول اللہ ملی تعلیم کی ذات کے لئے تھا.اور کسی کے لئے نہیں تھا.ملہ کے لوگ بھی اس معجزہ کے تو قائل تھے مگر وہ اس امر کے قائل نہ تھے کہ یہ معجزہ کسی اور
کے لئے ظاہر ہوا ہے.وہ اتنا تو سمجھتے تھے کہ دعائے ابرہیمی کے پورا ہونے کا یہ ایک ثبوت
ہے مگر یہ کہ احترام محمدی میں ایسا ہوا ہے اس کو وہ نہیں مانتے تھے.اگر مانتے تو مسلمان کیوں
نہ ہو جاتے.اللہ تعالیٰ اسی امر کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے اے احمقو! تم اسے اب بھی
نہیں مانتے.حالانکہ ہم نے اس کی پیدائش سے بھی پہلے اس کے لئے یہ معجزہ دکھا دیا تھا اور
جب ہم نے اس کی پیدائش سے بھی پہلے اس کے لئے یہ معجزہ دکھا دیا تھا اور جب ہم نے اس کی
پیدائش سے بھی پہلے اس کے لئے اپنے معجزات ظاہر کرنے شروع کر دئیے تھے تو تمہیں سمجھ لینا
چاہئے کہ ہم اب بھی اس کی زندگی کے آخری ایام تک اس کے لئے اپنے نشانات دکھاتے چلے
جائیں گے.اصحاب الفیل کہہ کر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ صرف ابر ہہ اور اس کا لشکر تباہ
نہیں ہوا بلکہ ان کی وہ پچھلی طاقت جو یمن میں تھی وہ بھی تباہ ہوگئی اور اس تباہی کا اتنا اثر پڑا کہ
عیسائیوں کے قومی بالکل ڈھیلے ہو گئے.اس تباہی میں اللہ تعالیٰ کی جو بہت بڑی حکمت کام کر
رہی تھی وہ یہ ہے کہ ایک بھاری حکومت کے کسی لشکر کا تباہ ہوجانا خطرہ کو کم نہیں کرتا بلکہ اور بھی
922
Page 931
بڑھا دیتا ہے.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ابرہہ اور اس کے لشکر کو ہی نہیں بلکہ اس قوت کو ہی کچل دیا جو
اس کے پیچھے کام کر رہی تھی.اصحاب الفیل سے نجاشی کی حکومت مراد ہے.ہاتھی عرب میں نہیں ہوتا تھا بلکہ حبشہ
سے آتا تھا.پس اصحاب الفیل سے مراد بھی حبشہ کی حکومت ہی ہے.اللہ تعالیٰ اس حکومت کا
ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْبِ الْفِيلِ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ
ہم نے اصحاب الفیل سے کیا کیا اور کس طرح ہم نے حبشہ کی حکومت کو ہی عرب سے مٹا دیا.گویا ہم نے صرف ابرہہ اور اس کے لشکر کو ہی شکست نہیں دی بلکہ عرب سے حبشہ کی حکومت
ہی مٹا دی تا کہ اس کی طرف سے بار بار حملہ کا خطرہ نہ رہے.اس سورۃ میں در حقیقت آخری زمانہ کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے اور مسلمانوں کو یہ
بتایا گیا ہے کہ محمد رسول اللہ علی ایم کی پیدائش سے بھی پہلے عیسائی دنیا نے آپ کے دین کو
روکنے اور اس کی ترقی کے امکانات کو مسدود کرنے کی کوشش کی تھی.چنانچہ جب وہ علامات
انہیں نظر آئیں جن سے یہ نتیجہ نکلتا تھا کہ نبی عربی دنیا میں پیدا ہونے والا ہے تو انہوں نے
خانہ کعبہ کا رخ کیا تا کہ عرب جس نقطہ مرکزی پر جمع ہو سکتے ہوں اسے توڑ دیا جائے اور وہ موعود
جس کا عرب میں شدت کے ساتھ انتظار کیا جارہا تھا اس کے راستہ میں روکیں پیدا ہو جائیں.لیکن اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ علیم کی آمد کے احترام اور آپ کے اعزاز میں خانہ کعبہ کو
گرنے نہیں دیا.اللہ تعالیٰ اس نشان کا ذکر کرتے ہوئے ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلاتا
ہے کہ پھر ایک زمانہ میں عیسائی دنیا محمد رسول اللہ علیم کی طاقت اور آپ کی قوت کو مٹانے
کی کوشش کرے گی اور تسلی دیتا ہے کہ تمہیں مایوس نہیں ہونا چاہئے.جس خدا نے محمد
رسول الله صل الا لیلی کے پیدا ہونے سے بھی پہلے آپ کا ادب اور احترام کیا تھا اس خدا کے متعلق
کون یہ خیال بھی کر سکتا ہے کہ وہ آپ کی پیدائش کے بعد، آپ کے دعوی نبوت کے بعد، آپ
923
Page 932
کی بے مثال اور حیرت انگیز قربانیوں کے بعد، آپ کی خدا تعالیٰ سے بے انتہا محبت کے
اظہار کے بعد، آپ کی اعلیٰ درجے کی نیک اور پاک جماعت دنیا میں قائم ہو جانے کے بعد،
آپ کی کامل اور ہر قسم کے نقائص سے منزہ شریعت لوگوں کے سامنے پیش ہو جانے کے بعد،
آپ کے دین اور مذہب کے تمام دنیا میں پھیل جانے کے بعد، اب اس ہتک کو برداشت
کرلے گا کہ اسے تباہ ہونے دے اور دشمن کو اس کے بد ارادوں میں کامیاب کر دے.کوئی
عقلمند جو ذرا بھی ان واقعات پر نگاہ رکھنے والا ہو وہ محمد رسول اللہ عالم کی نبوت پر ایمان رکھتے
ہوئے ایک لحظہ کے لئے بھی یہ بات نہیں مان سکتا کہ اس مقابلہ میں عیسائیت کو کامیابی
حاصل ہو سکتی ہے.یقیناً ایک مسلمان کے لئے اس میں شبہ کی کوئی گنجائش نہیں کہ وہ نگر جو
اسلام اور عیسائیت میں ہونے والی ہے اس کا وہی کچھ نتیجہ نکلے گا جواہر ہر کے وقت میں نکلا جبکہ
وہ خانہ کعبہ سے ٹکر لینے کے لئے آیا.لیکن افسوس کہ باوجود اس کے کہ مسلمانوں کے پاس
قرآن کریم موجود ہے.اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَب الْفِيلِ والی سورۃ موجود ہے اور وہ
اسے ہر روز دیکھتے اور پڑھتے ہیں انہیں اس بات پر یقین نہیں کہ اس لڑائی میں آخر اسلام فتحیاب
ہوگا اور عیسائیت ہارے گی.یقین سے میری مراد صرف منہ کی لاف و گزاف نہیں بلکہ وہ معقول
یقین مراد ہے جس کے ساتھ انسان کا عمل شامل ہوتا ہے.بے شک جہاں تک زبان کے
دعووں کا سوال ہے ہر مسلمان کہتا ہے کہ اسلام جیتے گا.لیکن جہاں تک اسلام کی فتح اور کامیابی
پر یقین کا سوال ہے ننانوے فیصدی مسلمان یہ یقین نہیں رکھتے کہ اس لڑائی میں اسلام جیتے گا.حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا الہام ہے کہ شخصے پائے من بوسید
و من گفتم که سنگ اسود منم ( تذکرہ صفحہ 35) ایک شخص نے میرے پاؤں کو
چوما اور میں نے کہا ہاں ہاں سنگ آسود میں ہی ہوں.درحقیقت ہر زمانہ کا مامور اس کی
جماعت کے لئے سنگِ آسود کا رنگ رکھتا ہے کیونکہ لوگ اسے چومنے اور اس کے اردگرد
اکٹھے رہتے ہیں اور اس طرح دین کو تقویت حاصل ہوتی ہے.پس اس زمانہ میں دین کی
924
Page 933
تقویت صرف حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے وابستہ ہے اور اس زمانہ میں روحانی
سنگ اسود آپ ہی ہیں گو جسمانی سنگ اسود وہی ہے جو خانہ کعبہ میں موجود ہے.اسی طرح یہ
سورۃ الفیل بھی آپ پر الہاما نازل ہوئی ہے.پھر جس طرح اصحاب الفیل کے پہلے حملہ میں اصل
مقصد رسول کریم صل ملک کو تباہ کرنا تھا اسی طرح اب جو احمدیت پر حملہ ہوا ہے وہ اسی لئے ہوا
ہے کہ ہندو بھی جانتا ہے اور سکھ بھی جانتا ہے اور مسیحی بھی جانتا ہے کہ اگر اسلام نے غلبہ پایا تو
احمدیت کے ذریعہ ہی غلبہ پائے گا.پس اب بھی اس کا اصل مقصد رسول کریم معلم کو تباہ کرنا
ہے کیونکہ مسیح موعود کا کام اپنا وجود منوانا نہیں بلکہ رسول کریم بیلی کا وجود منوانا ہے.آپ خود
فرماتے ہیں
وہ ہے.میں چیز کیا ہوں بس فیصلہ یہی ہے
لیکن جس طرح گزشتہ زمانہ میں خانہ کعبہ کو گرانے میں ابرہہ اور اس کا لشکر ناکام رہا تھا اسی
طرح ہم جانتے ہیں اور اس بات پر کامل یقین رکھتے ہیں کہ دنیا کی ساری طاقتیں اور قوتیں مل کر
بھی اگر اس سلسلہ کو جسے خدا نے محمد رسول اللہ علیم کا دین قائم کرنے کے لئے کھڑا کیا ہے
مٹانا چاہیں تو وہ ساری طاقتیں مل کر بھی اس سلسلہ کو مٹانہیں سکتیں.ہم جانتے ہیں کہ ہم کمزور
ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ہمارے اندر کوئی طاقت نہیں.لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آسمان کی
فوجیں ہماری تائید میں اتریں گی اور الم ترَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحُبِ الْفِيلِ کا نظارہ دنیا متواتر
دیکھتی چلی جائے گی.یہاں تک کہ وہی شخص جس کو مسلمانوں نے اپنی نادانی سے ٹھکرا دیا ہے
اسی کے ہاتھوں سے اسلام دنیا میں دوبارہ قائم ہوگا اور معترضین ہمارے سامنے نہایت شرمندگی
کے ساتھ وہی کچھ کہتے آئیں گے جو یوسف کے بھائیوں نے اس سے کہا.اور ہماری طرف
سے بھی انہیں یہی کہا جائے گا کہ لا تَثْرِیبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ
الراحمين.يکتنی عجیب بات ہے کہ غیر دنیا ، کا فردنیا، بے دین دنیا جس کا مقابلہ ہماری جماعت
کر رہی ہے وہ تو جانتی ہے کہ احمدیت کی اشاعت میں ہی عیسائیت کی موت ہے لیکن مسلمان
925
Page 934
یہ سمجھتے ہیں کہ احمدیت کی اشاعت میں نعوذ باللہ اسلام کی تباہی ہے.أَلَمْ يَجْعَلُ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيل.ترميم جاري مِن سِبِيْلِ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفِ مَأْتُولِ
کیا ( ان کو حملہ سے قبل بلاک کر کے ) ان کے منصو بہ کو باطل نہیں کر دیا اور (پھر) ان
کی لاشوں) پر ٹھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیجے (جو) ان (کے گوشت) کو سخت قسم کے
پتھروں پر مارتے ( اور نوچتے) تھے اس طرح اس نے انہیں غلہ کے بیرونی چھلکے کی طرح کر
دیا جس کے اندر کا دانہ کھایا گیا ہو.أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيْلٍ
عمالا کہ کر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اس نے عیسائیوں کا منصوبہ صرف اس وقت باطل
نہیں کیا جب وہ خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کے لئے آئے تھے.بلکہ اس نے بعد میں بھی ایک
لمبے عرصہ تک ان کے تمام منصوبوں کو خاک میں ملا دیا اور ان کی قوت کو کچل دیا تا
محمد رسول اللہ علیم کو بڑھنے اور پہنچنے کا موقع ملے اور آپ کی ترقی کے راستہ میں کوئی روک
واقع نہ ہو.چنانچہ اسلام کے مقابلہ میں عیسائی ایک لمبے عرصہ تک مغلوب رہے.مگر پھر
قرآن کریم کی ہی پیشگوئیوں کے مطابق دوبارہ عیسائیوں کو غلبہ حاصل ہوا.اور اب الہی فیصلہ
ہے کہ وہ مسیحیت کو دوسری شکست انشاء اللہ ہمارے ہاتھ سے دے گا.وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ
ابابیل جمع ہے جس کا مفرد کوئی نہیں لیکن بعض کے نزدیک اس کا مفرد را بول ہے.ابابیل کے متعلق عوام الناس یہ سمجھتے ہیں کہ اس جگہ ابابیل وہی پرندہ مراد ہے جسے اردو زبان
میں بھی ابابیل کہتے ہیں.مگر یہ درست نہیں.جس پرندے کو ہم ابابیل کہتے ہیں عربی زبان میں
اسے ابابیل نہیں بلکہ خفاش کہتے ہیں.پس اس جگہ ابابیل سے کوئی خاص پرندہ مراد نہیں بلکہ
اس کے معنے فرق یعنی جماعتوں کے ہیں.اور طیرا ابابیل سے مراد یہ ہے کہ
926
Page 935
جماعت در جماعت اور گروہ در گروہ پرندے آئے.یہ لفظ انسانوں کے لئے بھی استعمال
ہوتا ہے اور حیوانوں کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے اور پرندوں کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے.اگر گروہ در گروہ گھوڑے کسی جگہ کھڑے ہوں تو ان کے متعلق بھی ابابیل کا لفظ استعمال کر لیا جائے
گا.چنانچہ عربی زبان کا یہ محاورہ ہے کہ جَاءَتِ الْخَيْلُ آبَابِيلَ جس کے معنے جَمَاعَاتٍ مِنْ
ههنا وَهُهُنا کے ہیں.یعنی جماعت در جماعت اور گروہ در گروہ گھوڑے آئے کچھ یہاں سے
اور کچھ وہاں سے.اسی طرح اگر انسانوں کا کوئی بہت بڑا لشکر جمع ہو تو اسے بھی ابابیل کہہ
دیں گے اور مراد یہ ہوگی کہ بٹالین کے بعد بٹالین اور فوج کے بعد فوج آتی چلی گئی.پھر اس کے ایک معنے جماعات عظام “ کے بھی ہوتے ہیں یعنی بڑی بڑی جماعتیں.اور ابابیل کے معنے اَقَاطِيْعَ تَتْبَعُ بَعْضُهَا بَعْضاً کے بھی ہوتے ہیں.یعنی بڑے بڑے ٹکڑے
جو ایک دوسرے کے بعد متواتر آتے چلے جائیں.پس أَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْراً آبَابِیل کے یہ
معنے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف پرندے بھیجے جماعت در جماعت.کچھ یہاں سے
کچھ وہاں سے.وہ بڑے بڑے ٹکڑوں میں باری باری آتے تھے اور گروہ در گروہ تھے.اس میں
اسی طرف اشارہ ہے کہ چیچک سے اس لشکر میں سخت موت پڑی اور لاشیں میدان میں چھوڑ کر
باقی لوگ بھاگ گئے اور چاروں طرف سے گدھ اور چیل آکر وہاں جمع ہو گئے تا ان کی لاشوں
سے نوچ نوچ کر گوشت کھائیں.تَرْمِهِمْ حِجَارَ يا من سجيل
* سیچیل چکنی مٹی کے ڈلے کی طرح کے پتھر کو کہتے ہیں.پس سیچیل کے معنے ہیں
ایسا پتھر جو کئی پتھر کے ٹکڑوں اور مٹی کی تہوں سے بنا ہوا ہو یا پکی ہوئی مٹی کا پتھر جسے پنجابی زبان
میں کھنگر کہتے ہیں.تَرْمِيهِمُ بِحِجَارَةٍ مِن سجيل کے معنے عام محاورہ کے مطابق تو یہ ہیں کہ ان پر
سجیل مارتے تھے.لیکن اس کے یہ معنے بھی ہو سکتے ہیں کہ اُن کو سیٹجیل پر مارتے تھے.اور
927
Page 936
چونکہ مردار خور پرندوں کا یہ عام قاعدہ ہے کہ وہ مردہ کا گوشت لے کر پتھر پر بیٹھ جاتے ہیں اور
گوشت کو بار بار پتھر پر مارتے جاتے اور کھاتے جاتے ہیں ، نہ معلوم اسے نرم کرتے ہیں یا
اس کی صفائی کرتے ہیں.بہر حال چیلوں اور گدھوں کا یہ عام قاعدہ ہے کہ وہ گوشت کو کھاتے
ہوئے پتھر پر مارتے جاتے ہیں.اس لئے یہی درست ہے کہ باء کے معنے اس جگہ پڑ کے
لئے جائیں خصوصاً جبکہ یہ ثابت ہے کہ یہ لوگ چیچک سے مرے تھے اور ان کی لاشیں تمام
میدان میں پھیل گئی تھیں.پس آیت کا یہ مطلب ہے کہ مردار خور پرندے وہاں جمع ہو گئے اور
انہوں نے ان کی بوٹیاں نوچ نوچ کر اور پتھروں پر مار مار کر کھانی شروع کر دیں.باء کے معنے جو اس جگہ علی کے کئے گئے ہیں یہ لغت سے بھی ثابت ہیں اور استعمال قرآن
سے بھی ثابت ہیں.اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس تباہی کا نقشہ کھینچا ہے جو اصحاب الفیل پر آئی.آپ
لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ چیلیں اور گدھ اور کوے اور دوسرے مُردار خور جانور جب کوئی بوٹی
کھاتے ہیں تو کس طرح کھاتے ہیں.وہ مردار کی بوٹی توڑ کر ایک طرف جا بیٹھتے ہیں اور پتھر پر
بیٹھ کر کبھی اسے ایک طرف سے مارتے ہیں کبھی دوسری طرف سے.اور اس طرح بار بار اس
کو پتھر پر مارنے کے بعد کھاتے ہیں.یہی کیفیت اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ظاہر کی ہے
اور بتایا ہے کہ جب ہم نے چیچک سے ان کو مار دیا تو چونکہ وہ ہزاروں ہزار تھے اس لئے
مردوں کے ڈھیروں پر گروہ در گروہ اور جماعت در جماعت چیلیں اور گدھ اور کوے اور
دوسرے مردار خور جانور ا کٹھے ہو گئے.اور وہ بڑے بڑے جرنیل اور کرنیل جن کے اردگرد
ہر وقت پہرے رہتے تھے اور جو بڑی بڑی اعلیٰ وردیاں پہن کر اکڑ اکڑ کر چلتے تھے ان کی
بوٹیاں نوچ نوچ کر اور پتھروں پر مار مار کر کھانے لگے.ملا اس کے بعد کیا ہوا.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ.اس نے
انہیں دانہ کھائے ہوئے سٹے کی طرح کر دیا.جس طرح اندر سے گندم کو کیڑا کھا جائے اور اوپر کا
928
Page 937
صرف چھلکا باقی رہ جائے.اسی طرح ان کی کیفیت ہو گئی.ان کا گوشت سب گدھیں اور
چیلیں اور کوے کھا گئے اور باقی صرف ہڈیاں رہ گئیں یا چھڑا اور سر کے بال رہ گئے.یہ وہ واقعہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ میں بیان فرمایا اور جو تمام آیات کے ساتھ
مطابقت رکھتا ہے.افسوس ہے کہ مفسرین نے بجائے اس کے کہ حقیقت پر غور کرتے ایسے
ایسے لاطائل اور بے بنیاد اور لغو قصے اس کے متعلق اپنی تفسیروں میں بھر دیے ہیں کہ جن کو پڑھ
کر انسان کی اپنی عقل بھی حیران ہوتی ہے اور دشمن کو بھی اسلام پر ہنسی اڑانے کا موقع ملتا ہے.(ماخوذ از تفسیر کبیرزیر سورة الفيل )
929
Page 939
XXXXXXX
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
لا يُلفِ قُرَيْشن
الفهمُ رِحْلَةَ الشَّتَاءِ وَالصَّيْفِ
فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ
الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوعٍ
وَأَمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ أَ
سورة القريش
1 - (میں) اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا
( اور ) بار بار رحم کرنے والا ہے (پڑھتا ہوں)
2.دوسری اغراض کے علاوہ ) قریش کے دلوں
کو مانوس کرنے کے لئے.یعنی ان کے دلوں کو گرمائی اور سرمائی سفروں سے
مانوس کرنے کے لئے (ہم نے ابرہہ کو تباہ کیا )
5-4.پس انہیں لازم ہے کہ وہ ( قریش ) اس گھر
( یعنی کعبہ) کے مالک کی عبادت کریں جس نے
انہیں ( ہر قسم کی ) بھوک ( کی حالت ) میں کھانا کھلایا
اور ( ہر قسم کی ) خوف کی حالت میں امن بخشا.931
Page 940
حضرت خلیفہ المسیح الاول رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:
اس سورۃ شریف میں جو یہ حکم ہوا ہے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو
بھوک سے غنی کرنے کے لئے کھانا کھلایا.یہ آیت شریف حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام
والبرکات کی اس دُعا کے مطابق ہے کہ میرے پروردگا اس شہر کو امن کی جگہ بنا.اس دعائے
ابراہیمی کی قبولیت کے سبب قریش بڑے عیش و آرام میں زندگی بسر کرتے تھے.حالانکہ ان
کے گرد و نواح کی مخلوق بلاکت میں پڑی ہوئی تھی.اسی مضمون کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنی
پاک کلام میں سورۃ نحل میں بھی اشارہ فرمایا ہے.اللہ تعالیٰ نے ایک گاؤں کی مثال بیان
فرمائی ہے جس کے باشندے اطمینان کے ساتھ زندگی گزارتے تھے.ہر طرف سے اس کو رزق
با فراغت پہنچتا تھا.پھر ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی جس پر خدا نے ان پر
بھوک اور خوف کا عذاب وارد کیا.جو اُن کی اپنی بدعملیوں کا نتیجہ تھا.ماخوذ از حقائق الفرقان زیر سورۃ القریش )
حضرت خلیفہ اسیح الثانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:
یہ سورۃ متگی ہے.م اس سورۃ کے دو نام ہیں.اسے قریش بھی کہتے ہیں اور اس کا ایک نام حدیثوں
میں لایلف بھی آتا ہے.لائلفِ قریش در حقیقت تین لفظ ہیں لیکن بعض لوگ جن کو پورے
معنے نہیں آتے وہ غلطی سے لایلف کو ایک اور قریش کو دوسرا لفظ سمجھ لیتے ہیں.جیسا کہ میں نے بتایا ہے آخری پارہ کی سورتیں یکے بعد دیگرے اسلام کے ابتدائی اور آخری
زمانہ سے تعلق رکھتی ہیں یعنی ایک سورۃ اگر ابتدائے زمانہ اسلام کے متعلق ہوتی ہے تو دوسری سورۃ
آخری زمانہ اسلام کے متعلق ہوتی ہے.یہ سورۃ اسلام کے ابتدائی زمانہ کے متعلق ہے جیسا کہ
932
Page 941
الَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْبِ الْفِيلِ والی سورۃ آخری زمانہ کے متعلق تھی.اس سورۃ کا پہلی سورۃ سے تعلق ہے کہ پہلی سورۃ میں یہ بتایا گیا تھا کہ کس طرح
خدا تعالیٰ نے کعبہ کی حفاظت کی اور یہ کہ آئندہ زمانہ میں بھی وہ کعبہ کی اسی طرح حفاظت
فرمائے گا.آئندہ زمانہ کی بات تو ابھی دنیا نے دیکھی نہیں جب وقت آئے گا دنیا اس نظارہ کو بھی
دیکھ لے گی.لیکن پہلا نشان مکہ والے دیکھ چکے ہیں.اس سورۃ میں اللہ تعالیٰ اسی نشان کی طرف
اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اس عظیم الشان نشان کو دیکھتے ہوئے پھر بھی مکہ کے لوگ دنیا
کی طرف زیادہ توجہ کرتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی طرف کم توجہ کرتے ہیں حالانکہ اتنا بڑا نشان
دیکھنے کے بعد انہیں یہ یقین ہو جانا چاہئے تھا کہ خانہ کعبہ سے تعلق رکھنے والوں اور اس کی سچی
خدمت کرنے والوں
کا اللہ تعالیٰ خود حافظ و ناصر ہوتا ہے اور اس وجہ سے انہیں دنیا کی طرف کم
توجہ کرنی چاہئے تھی مگر افسوس ہے کہ ان کی حالت اس کے برعکس ہے.دوسرا تعلق اس سورۃ کا پہلی سورۃ سے یہ ہے کہ پہلی سورۃ میں کعبہ کے دشمنوں کا انجام بتایا
گیا تھا.اب اس سورۃ میں اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ سے محبت رکھنے والوں کے انجام کا ذکر کرتا ہے.گویا ایک میں دشمنوں کا انجام
بتایا اور دوسری میں دوستوں سے خواہ وہ گنہگار ہی تھے اپنے تعلق کا
اظہار کیا اور ان پر اپنے احسان کا ذکر کیا.میں اوپر بتا چکا ہوں کہ ابرہہ اور اس کے لشکر کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ کوئی اتفاقی امر نہیں تھا
اس امر کا مزید ثبوت ان دونوں سورتوں کا یکے بعد دیگرے آنا ہے.دنیا میں یہ ایک مسلمہ اصول
ہے کہ جب کسی چیز کے دونوں پہلو بیان کر دئیے جائیں اور وہ دونوں پہلوؤں سے کامل نظر آتی
ہو تو اس پر یہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ وہ اتفاقی ہے.چونکہ اصحاب الفیل کے واقعہ پر یہ
اعتراض ہو سکتا تھا کہ کیوں نہ اسے اتفاقی حادثہ قرار دے دیا جائے.اس لئے اللہ تعالیٰ نے
سورۃ ایلف کے ذریعہ اس اعتراض کو دور کر دیا.پہلی سورۃ میں یہ بتایا گیا تھا کہ جس نے خانہ کعبہ سے دشمنی کی اس سے ایسا ایسا سلوک ہوا.اب سورۃ ایلف میں یہ بتاتا ہے کہ جس نے خانہ کعبہ سے دوستی کی اس سے اس اس
933
Page 942
طرح سلوک ہوا.اگر خانہ کعبہ سے دشمنی رکھنے والوں کی سخت ذلت اور رسوائی ہوئی اور دوسری
طرف خانہ کعبہ سے دوستی رکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں سے نوازا ہے تو ہر شخص ان
دونوں متقابل باتوں کو دیکھ کر سمجھ سکتا ہے کہ یہ جو کچھ ہوا بالا رادہ ہوا.اتفاقی امر نہیں تھا.قریش در اصل نام ہے بنو نضر بن کنانہ کا.جیسے خود رسول کریم صلی علیم سے یہ مروی
ہے.چنانچہ آپ سے جب سوال کیا گیا کہ قریش کن کو کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا القريش
من ولد النَّضْرِ - نضر کی جو اولاد ہے وہ قریشی کہلاتی ہے.اسی طرح احادیث میں آتا ہے
قَالَ إِنَّ اللهَ اصْطَفَى كَنَانَةٌ مِنْ بَنِي اِسْمعِيل وَاصْطَفَى مِنْ كَنَانَةَ قُرَيْشًا وَاصْطَفَى مِنْ
قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِمٍ وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِم (سراج منیں) یعنی اللہ تعالیٰ نے کنانہ کو
بنی اسمعیل میں سے فضیلت دی.کنانہ میں سے قریش قبیلہ کو فضیلت دی.قریش قبیلہ میں سے
اللہ تعالیٰ نے بنو ہاشم کو فضیلت دی اور بنو ہاشم میں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے فضیلت دی.اس
حدیث میں رسول کریم صلیم نے قریش کو بنو کنانہ قرار دیا ہے.اور دوسری حدیث میں آتا
ہے کہ من ولد النضير - دراصل کنانہ کے کئی بیٹے تھے.رسول کریم صل الا لیلی نے یہ تشریح فرما
دی کہ ان میں سے صرف نظر کی اولا د قریش کہلاتی ہے ساری اولاد نہیں.حقیقت یہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے تو حضرت اسمعیل کو خانہ کعبہ میں اس لئے بٹھایا
تھا کہ وہ خانہ کعبہ کی حفاظت کریں.لیکن حضرت اسمعیل کی اولاد میں آگے یہ جوش دیر تک
قائم نہ رہا.جیسے آج بعض سید چور بھی ملتے ہیں اور ڈا کو بھی ملتے ہیں.کچھ نسل تک تو انہوں نے
اِس وعدہ کو یا درکھا لیکن اس کے بعد وہ اس وعدے کو بھول گئے اور حضرت اسمعیل کی اولاد
سارے عرب میں پھیل گئی.بلکہ عرب کے علاوہ شام تک بھی چلی گئی.آخر قرب زمانہ نبوی میں
قصی بن حکیم بن نضر کے دل میں خیال آیا کہ ابراہیمی وعدہ کو تو ہم پورا نہیں کر رہے.ہمارے
دادا نے تو یہ کہا تھا کہ تم یہاں رہو.اس گھر کی صفائی رکھو.خانہ کعبہ کے حج اور طواف کے لئے
جولوگ آئیں ان کی خدمت کرو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنا وقت گزارو.مگر ہم ادھر اُدھر
بکھر گئے اور اس خدمت کو جو ہمارے دادا نے ہمارے سپرد کی تھی بھول گئے.یہ خیال ان کے
934
Page 943
دل میں اتنے زور سے پیدا ہوا کہ انہوں نے بنو نضر کے اندر یہ تحریک شروع کی کہ آؤ ہم لوگ
اپنے سارے کام کاج چھوڑ کر مکہ میں جابسیں اور خانہ کعبہ کی خدمت کریں.یہ مناسب نہیں کہ
ہم دنیوی اغراض کے لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وعدہ کو بھول جائیں اور جو نصیحت
انہوں نے اپنی اولاد کو کی تھی اس کی پروا نہ کریں.انہوں نے جب ہمارے سپرد یہ کام کیا تھا کہ
ہم خانہ کعبہ کی خدمت کریں تو ہمارا فرض یہی ہے کہ ہم مکہ میں چلے جائیں اور خانہ کعبہ کی
خدمت کریں.چنانچہ ان کی قوم نے ان کی بات مان لی اور وہ سب مگہ میں اکٹھے ہو گئے.یہ
ایک بہت بڑی قربانی تھی جو انہوں نے کی.وہ باہر بڑی بڑی اچھی چراگاہوں میں رہتے
تھے، وہ تجارتیں بھی کرتے تھے، وہ زمینداریاں بھی کرتے تھے.وہ اور کئی قسم کے کاروبار میں
بھی حصہ لیتے تھے مگر یکدم ساری قوم نے اپنی زمینیں چھوڑیں، گلہ بانی چھوڑی، زمینداری
چھوڑی، تجارت چھوڑی اور ایک وادی غیر ذی زرع میں جہاں آمدن کی کوئی صورت نہیں تھی
آبیٹھے.میں سمجھتا ہوں اس قربانی کی مثال دنیا کی تاریخ میں نہیں مل سکتی کہ ایک قوم کی قوم
اپنے پیشے چھوڑ کر محض اس لئے ایک وادی غیر ذی زرع میں آبیٹھی کہ ان کے دادا ابراہیم نے
اپنی اولاد کو یہ نصیحت کی تھی کہ تم مگہ میں رہو اور جولوگ یہاں حج اور طواف اور اللہ تعالیٰ کی عبادت
کے لئے آئیں ان کی خدمت کرو.یہ ایک بہت بڑی قربانی تھی جو انہوں نے کی.پس چونکہ یہ لوگ متفرق ہونے کے بعد پھر اپنے گھر بار چھوڑ کر مکہ میں جمع ہو گئے تھے تا کہ
ابراہیمی وعدہ کو پورا کریں اس لئے ان کا نام قریش رکھا گیا....قرش کے معنے جمع کرنے
کے ہیں.پس قریش وہ قبیلہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشگوئی کو پورا کرنے کے
لئے مکہ میں جمع کیا گیا اور اسی لئے ان کا نام قریش ہوا.انہیں اس لئے قریش نہیں کہتے تھے کہ
وہ باقی تمام قبائل عرب پر غالب تھے اور قرش کی طرح ان کو کھا جاتے تھے.قریش کو
عربوں میں یہ شہرت اور عزت رسول کریم علیہ کے قریب زمانہ میں حاصل ہوئی ہے ورنہ اس
سے پہلے تو یہ لوگ مجاوروں کی طرح وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور قبائل عرب پر ان کو کوئی غلبہ
حاصل نہیں تھا.پس قریش کے معنے ہیں وہ قبیلہ جو اردگرد سے اکٹھا کر کے قصی بن کلاب بن
935
Page 944
نضر نے مکہ میں آبٹھایا تھا یا یوں کہو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کچھ اولاد قریش کہلائی
کیونکہ وہ اردگرد سے لا کر مکہ میں بیت اللہ کی خدمت کے لئے لا بٹھائی گئی تھی.ا سوال پیدا ہوتا ہے کہ قریش تو تصغیر کا صیغہ ہے اور معنے یہ ہیں کہ مکہ میں جمع ہو جانے
والا ایک چھوٹا سا ٹکڑایا ایک چھوٹا سا گروہ.پھر کیا وجہ ہے کہ آلِ اسماعیل کو ایک چھوٹا سا گروہ یا
چھوٹا سا ٹکڑا کہا گیا ہے؟
اس کا جواب یہ ہے کہ حکم تو سارے بنو اسمعیل کو تھا کہ وہ مکہ میں رہیں.اللہ تعالیٰ کی عبادت
اور پرستش کریں اور جو لوگ حج اور طواف کے لئے آئیں ان کی خدمت کریں.مگر چونکہ
بنو کنانہ میں سے صرف نضر بن کنانہ کی اولا د مکہ میں آکر بسی اور چونکہ وہ سارے بنو اسماعیل میں
سے ایک چھوٹا سا گروہ تھا اس لئے وہ قریش کہلائے.یہ بتانے کے لئے کہ ہم تھوڑے سے
آدمی ہیں جو اپنے دادا ابراہیم کی بات مان کر یہاں جمع ہو گئے ہیں تا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت
کریں اور جولوگ خانہ کعبہ کے حج کے لئے آئیں ان کی خدمت کریں.اور شاید اس نام میں
اس طرف بھی اشارہ ہو کہ دوسرے قبائل کو بھی مکہ میں جمع ہونے کی تحریک ہوتی رہے اور
حضرت اسمعیل علیہ السلام کی باقی اولاد کے دل میں بھی یہ خیال پیدا ہوتا رہے کہ جب ہم سے
تھوڑے سے لوگ وہاں بس گئے ہیں اور انہوں نے ہر قسم کی تکلیف کو برداشت کر لیا ہے تو ہم
بھی تو اولاد ابراہیم میں سے ہیں اگر ہم بھی وہاں جابسیں اور اپنے دادا کے حکم کو مان لیں تو اس
میں حرج کیا ہے.پس شاید اس تصغیر میں ایک یہ بھی حکمت ہو کہ اس نام سے باقی بنو اسمعیل
کے دل میں تحریک ہوتی رہے اور وہ بھی اپنے دادا ابراہیم کی بات کو مانتے ہوئے خدا تعالیٰ
کے گھر کی خدمت کے لئے مکہ میں آبسیں.پس ممکن ہے کہ اس نام سے انہوں نے دوسرے
قبائل کے اندر تحریک کرنے کی ایک صورت پیدا کی ہو اور مکہ میں ان کے جمع ہونے کے لئے
ایک تحریک جاری کی ہو.غرض قصی بن کلاب کی تحریک پر یہ لوگ آئے اور مکہ میں بس گئے.مگر ابتدا میں عرب کی
936
Page 945
توجہ حج کی طرف اتنی نہیں تھی کہ وہ مکہ میں کثرت سے آتے جاتے اور خانہ کعبہ کی برکات سے
مستفیض ہوتے.اس کا ثبوت یہ ہے کہ وہ قوم جو اپنے دادا کی ہدایت اور خدا تعالیٰ کی طرف
سے بڑی بڑی پیشگوئیوں کے باوجود خانہ کعبہ کو چھوڑ کر چلی گئی.اگر حاجی کثرت سے مکہ میں
آتے ہوتے تو ان لوگوں کے رزق کے سامان پیدا ہوتے رہتے اور ان کو مکہ چھوڑنے کی
مجبوری پیش نہ آتی.پس آلِ اسمعیل کا مکہ کو چھوڑ کر دوسرے عرب علاقوں میں پھیل جانا اس امر
کا ثبوت ہے کہ اس وقت تک خانہ کعبہ کے حج کا رواج عرب میں کم تھا اور بہت تھوڑے
لوگ حج کے لئے آتے تھے....پس اگر بنو اسمعیل نے مکہ چھوڑا تو یقیناً اس کے معنے یہ تھے کہ اس زمانہ میں بہت ہی کم لوگ
حج کیا کرتے تھے اور ان کے گزارہ کی کوئی صورت نہیں
تھی.اس لئے یہ لوگ مکہ سے نکلے اور
تمام عرب میں پھیل گئے.جب قصی بن کلاب کی تحریک پر یہ لوگ مکہ میں جابسے تو یہی دقت
ان کو پیش آئی.وہ بس تو گئے مگر چونکہ حاجی بہت کم آتے تھے اور یہ لوگ وہیں رہتے تھے باہر
کہیں آتے جاتے نہیں تھے.نتیجہ یہ ہوا کہ وہ سخت تنگی اور محسر کی حالت میں مبتلا ہو گئے اور ان
کے گزارہ کی کوئی صورت نہ رہی بلکہ بعض لوگوں کی تو فاقہ تک نوبت پہنچ گئی اور ان کے لئے
اپنی عزت اور زندگی کا قائم رکھنا مشکل ہو گیا.مگر پھر بھی قریش کو داد دینی پڑتی ہے کہ انہوں
نے ان تمام صعوبتوں کو بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کیا اور اپنی زبان پر وہ ایک لمحہ
کے لئے بھی حرف شکایت نہ لائے.اوّل تو ان کی یہی بہت بڑی قربانی تھی کہ
انہوں نے اپنے کام کاج چھوڑے، پیشوں کو ترک کیا، تجارتوں کو نظر انداز کیا، زمینداریوں
سے منہ موڑا اور ایک وادی غیر ذی زرع میں جہاں روزی کا کوئی سامان نہ تھا، اہل وعیال کو
لے کر رہنا شروع کر دیا.مگر پھر بھی کوئی کہہ سکتا تھا کہ قریش کا مکہ میں بسنا کوئی ایسی قربانی
نہیں جس کی تعریف کی جا سکے کیونکہ مکہ کی عزت لوگوں میں بہت پھیلی ہوئی تھی اور لوگ وہاں
حج کے لئے آتے جاتے تھے.اس لئے ممکن ہے وہ دولت یا عزت کی خواہش کی وجہ سے مگہ
937
Page 946
میں جا کر بس گئے ہوں.سوچونکہ یہ اعتراض پیدا ہو سکتا تھا اس لئے خدا تعالیٰ نے ان کی عزت
ظاہر کرنے کے لئے پھر دوسری دفعہ ان کو قربانی کا موقع دیا.مگہ میں بسنے کی وجہ سے ان کے
گزارہ کی کوئی صورت نہ رہی.حج کی طرف عربوں کو بہت کم توجہ تھی.نتیجہ یہ ہوا کہ فاقوں کی
وجہ سے جانوں کے اتلاف تک نوبت پہنچ گئی.یہ لوگ کافر بھی تھے ، مشرک بھی تھے، بے دین
بھی تھے اور ان میں سینکڑوں قسم کی خرابیاں پائی جاتی تھیں لیکن اس قوم میں بعض غیر معمولی
خوبیاں بھی تھیں.مکہ کے لوگوں میں سے جب کسی خاندان کے پاس کھانے پینے کا سامان بالکل
ختم ہو جاتا اور اس کی حالت غیر ہو جاتی.وہ دوست بھی جو ان کی حالت سے آگاہ ہوتے مدد
سے لاچار ہوتے کیونکہ وہ خود بھی غریب ہی ہوتے تھے تو وہ فاقہ کش لوگ قصی پر اعتراض
نہیں شروع کر دیتے تھے کہ اس نے ہمیں غلط تعلیم دی تھی.ہم مکہ چھوڑ کر چلے جائیں گے.وہ یہ
نہیں کہتے تھے کہ ہم نے بیوقوفی کی کہ ایسی جگہ آیسے جہاں روٹی کا کوئی سامان نہیں تھا بلکہ وہ
خاندان اسی وقت اپنا خیمہ اٹھا کر مکہ سے ذرا باہر چلا جاتا ( مکانوں کا رواج عرب میں بہت کم
تھا بلکہ اب تک بھی بادیہ کے لوگ خیموں میں رہتے ہیں) اور مکہ سے دو تین میل پرے اپنا خیمہ
لگا لیتا اور اپنے بیوی بچوں کو بھی وہیں لے جاتا تا کہ اس کے رشتہ داروں، دوستوں اور محلہ
والوں کو اس کی اس بُری اور خراب حالت کا پتہ نہ لگے.اور وہیں وہ سب کے سب بھو کے مر
جاتے.میں سمجھتا ہوں یہ اس قسم کی قربانی ہے کہ اس کی مثال دنیا کی تاریخ میں نہیں مل سکتی.لوگ
بھوکے ہوتے ہیں تو وہ فوراً کسی دوسری جگہ جا کر اپنی حالت کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے
ہیں.وہ دوسروں سے سوال کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے اور صبر اور برداشت کی قوت کو
بالکل کھو بیٹھتے ہیں.د وہ لوگ مشرک تھے لیکن ان میں محمد رسول اللہ صلم کی امت بننے کی قابلیت
خدا تعالیٰ پیدا کر رہا تھا.یہ کتنی بڑی قربانی ہے کہ وہ مگہ سے کچھ فاصلہ پر خیمے لگا لیتے اور اپنے
938
Page 947
بیوی بچوں سمیت وہیں بھوک سے تڑپ تڑپ کر مر جاتے مگر مکہ کو نہ چھوڑتے تھے اور نہ
دوسرے لوگوں سے سوال کرتے.اس سے ایک طرف تو ان کے اس جوش کا پتہ لگتا ہے جو اُن
کے دلوں میں خانہ کعبہ کی خدمت کے متعلق تھا اور دوسری طرف ان کی قناعت کا بھی اظہار ہوتا
ہے کہ وہ لوگوں پر بار نہیں بنتے تھے.کسی سے کچھ مانگتے نہیں تھے.الگ تھلگ ایک خیمہ
میں پڑے رہتے اور وہیں سب کے سب مرجاتے.میں سمجھتا ہوں ہماری جماعت جو اس امر کی مدعی ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی نازل کی ہوئی
تعلیم پر ایمان رکھتی اور اس کے نور کی حامل ہے اس کے افراد کو بھی اس سے سبق حاصل کرنا
چاہئے.خصوصاً حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد اور آپ کے خاص اتباع کی اولاد
کو میں اُن کے اس فرض کی طرف توجہ دلاتا ہوں.میں دیکھتا ہوں کہ دین کے لئے قربانی اور
ایثار کا وہ مادہ ابھی تک ان میں پیدا نہیں ہوا جو احمدیت میں داخل ہونے اور حضرت مسیح موعود
علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے کے بعد ان میں پایا جانا چاہئے تھا.ان کا قدم نہایت سست
ہے اور ان کے اندر قربانی اور ایثار کا مادہ ابھی بہت کم ہے.یقیناً اس معیار کے ساتھ ہم کبھی
بھی دنیا پر غالب نہیں آسکتے.جب تک ہم میں سے ہر شخص یہ نہیں سمجھ لیتا کہ وہ غرض جس کے
لئے وہ اس سلسلہ میں شامل ہوا ہے اور وہ مقصد جس کے لئے اس نے بیعت کی ہے وہ دوسری
تمام اغراض اور دوسرے تمام مقاصد پر مقدم ہے اس وقت تک یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس نے
اپنے ایمان کا کوئی اچھا نمونہ دکھایا ہے.بلکہ میرے نزدیک حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ
والسلام کی اولاد کے لئے تو ایسے کام کرنا جن سے دین کی خدمت میں روک پیدا ہو قطعی طور پر
ناجائز ہے اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ ویسا ہی دنیا دار شخص ہے جیسے کوئی اور.لیکن
دوسروں کو بھی یہ سمجھ لینا چاہئے کہ ان کے اندر یہ مادہ ہونا چاہئے کہ جب دین کی طرف سے انہیں
آواز آئے وہ اپنے تمام کام کاج چھوڑ کر فوراً چلے آئیں اور اپنے آپ کو دینی خدمات میں مشغول
کردیں.اب اگر وہ دنیا کا کام کرتے ہیں تو اس لئے کہ ابھی دین کو ان کی ضرورت پیش نہیں
939
Page 948
آئی.لیکن اگر ضرورت پیش آجائے تو پھر ان کو یا درکھنا چاہئے کہ بیعت کے وقت انہوں نے یہ
عہد کیا تھا کہ ہم دین کو دنیا پر مقدم رکھیں گے.اس دین کو دنیا پر مقدم رکھنے کے عہد کے آخر
کوئی معنے تو ہونے چاہئیں.اس کے تم کوئی ادنیٰ سے ادنی معنے کر لو.آخر کسی نہ کسی چیز کو
تمہیں بہر حال اپنے کاموں پر مقدم رکھنا پڑے گا.اگر اس عہد میں تم مال شامل کرو تو تمہیں مال
پر دین کو مقدم رکھنا پڑے گا.اگر جان شامل کرو تو تمہیں جان پر دین کو مقدم رکھنا پڑے گا.اگر
خدمت شامل کرو تو تمہیں ہر قسم کی خدمت پر دین کو مقدم رکھنا پڑے گا.بہر حال کوئی نہ کوئی
مفہوم تمہیں اس اقرار کا تسلیم کرنا پڑے گا اور جب یہ اقرار ہر احمدی نے کیا ہے تو ہماری جماعت
کے افراد کو سوچنا چاہئے کہ اس اقرار کے بعد وہ کیا کر رہے ہیں.ان کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ دین
کو دنیا پر مقدم رکھتے ہیں مگر سوال یہ ہے کہ کیا ایسے احمدی موجود ہیں جو سو میں سے 51 روپے
دین کے لئے خرچ کرتے ہوں.مقدم کے معنے تو یہ ہوتے ہیں کہ میں اور کاموں پر اس کام کو
ترجیح دیتا ہوں.اگر انہیں سورو پید اپنے اخراجات کے لئے ملتا ہے اور وہ دیانتداری کے ساتھ
اپنے تمام کاموں پر دین کو مقدم سمجھتے ہیں تو اس کا ثبوت اسی طرح مل سکتا ہے کہ وہ سو میں سے
51 روپے دین کے لئے خرچ کرتے ہوں.مگر کیا وہ ایسا کرتے ہیں؟ کیا وہ دن رات کے 24
گھنٹوں میں سے تیرہ گھنٹے دین کے کاموں پر صرف کرتے ہیں؟ یا قربانی اور ایثار کے لحاظ
سے وہ اپنے بیوی بچوں اور دوسری چیزوں پر دین کو مقدم کرتے ہیں؟ یا وطن کے لحاظ سے وہ
دین کو دنیا پر مقدم سمجھتے ہیں؟ یا جان کے لحاظ سے وہ دین کو دنیا پر مقدم سمجھتے ہیں ؟ آخر کوئی ایک
چیز تو ہونی چاہئے جس کے لحاظ سے وہ کہہ سکتے ہوں کہ ہم دین کو دنیا پر مقدم کر رہے ہیں.اگر ہر احمدی اس نقطہ نگاہ سے غور کرے اور اسے اپنے اندر ایک بات بھی ایسی نظر نہ آئے
جس میں وہ دین کو دنیا پر مقدم کر رہا ہو تو اسے سمجھ لینا چاہئے کہ یہ محض منافقت کی بات ہے کہ وہ
دعوی تو یہ کرتا ہے کہ میں دین کو دنیا پر مقدم کرتا ہوں مگر عمل یہ ہے کہ وہ کسی ایک چیز کے
لحاظ سے بھی دین کو دنیا پر مقدم نہیں کرتا.آخر کوئی ایک چیز تو ہونی چاہئے جس کے متعلق وہ کہہ
940
Page 949
سکے کہ میں فلاں چیز کے لحاظ سے دین کو دنیا پر مقدم کر رہا ہوں.اور اس عہد کا کوئی نہ کوئی
مفہوم تو ہونا چاہئے.اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ عہد ہم سے صرف اتنا تقاضا نہیں کرتا کہ ہم کسی
ایک پہلو میں دین کو دنیا پر مقدم کریں بلکہ ہر بات میں اور اپنے ہر کام میں ہمارا فرض ہے کہ ہم
دین کو دنیا پر مقدم کریں.مگر سوال تو یہ ہے کہ جو شخص اپنے ہر کام میں دین کو دنیا پر مقدم نہیں کر
سکتا اسے کم از کم یہ تو کوشش کرنی چاہئے کہ وہ کسی ایک کام میں ہی دین کو دنیا پر مقدم رکھے
تا کہ وہ کہہ سکے کہ میں اس عہد کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں.یہ کوشش خواہ وہ مال
کے لحاظ سے کرے، خواہ تجارت کے لحاظ سے کرے، خواہ پیشہ کے لحاظ سے کرے، خواہ وطن کی
محبت کے لحاظ سے کرے خواہ ملازمت کے لحاظ سے کرے، خواہ اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں
کے تعلقات کے لحاظ سے کرے، خواہ عبادت کے لحاظ سے کرے، خواہ قربانی اور ایثار کے لحاظ
سے کرے، بہر حال کوئی ایک چیز تو ایسی ہونی چاہئے جسے وہ دنیا کے سامنے پیش کرسکتا ہو اور
کہہ سکتا ہو کہ جن کاموں کا مجھے موقع ملا ہے ان میں میں نے دین کو دنیا پر مقدم کرلیا ہے اور جو
باقی کام ہیں ان میں بھی میں پوری طرح تیار ہوں کہ اس عہد کے مطابق عمل کرنے کی کوشش
کروں.لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو اسے سمجھ لینا چاہئے کہ اس کا دعویٰ ایمان محض ایک منافقانہ
فعل ہے جو اس کے کسی کام نہیں آسکتا.تم قریش کے اس واقعہ پر غور کرو اور دیکھو کہ باوجود اس کے کہ یہ لوگ سچے دین کے حامل
نہیں تھے، باوجود اس کے کہ یہ لوگ بت پرست تھے، باوجود اس کے کہ یہ لوگ بے دین
تھے.انہوں نے کتنی عظیم الشان قربانی کی.یہ لوگ اپنی قوم پر بوجھ نہیں بنے.انہوں نے کہا
ہم خدا کے لئے آئے تھے.ہماری قوم کا کیا حق ہے کہ وہ ہماری خدمت کرے.وہ خیمہ اٹھا کر
مکہ سے باہر چلے جاتے.باپ کے سامنے اس کا بیٹا مرتا، ماں کے سامنے اس کی بیٹی مرتی ، بیوی
کے سامنے اس کا خاوند مرتا ، بچوں کے سامنے ان کا باپ مرتا، دوست کے سامنے دوست اور رشتہ
دار کے سامنے رشتہ دارم تا مگر کیا مجال کہ ان کی زبان پر کوئی شکایت آتی.کیا مجال کہ وہ اس جگہ
941
Page 950
کو چھوڑنے کے لئے تیار ہو جاتے.اتنی بڑی مصیبت دیکھنے کے بعد بھی انہوں نے اس جگہ کو
نہیں چھوڑا.وہ کسی معجزہ کو دیکھ کر وہاں نہیں آئے تھے.وہ کسی نشان کو دیکھ کر وہاں نہیں آئے
تھے، وہ کسی تازہ تعلیم پر ایمان لا کر وہاں نہیں آئے تھے.دوہزار سال پہلے ان کے دادا ابراہیم
نے ایک بات کہی تھی اور وہ اپنے دادا کے وعدہ کے مطابق اس سرزمین میں آبسے.ان پر فاقے
آئے مگر انہوں نے اس جگہ کو نہ چھوڑا.انہوں نے سالہا سال غربت اور تنگی اور افلاس میں اپنی
زندگی کے دن بسر کئے.ان کے پاس کھانے کے لئے کچھ نہیں تھا.ان کے پاس گزارہ کا کوئی
سامان نہیں تھا.مگر انہوں نے کہا ہم اس مقام کو اب نہیں چھوڑ سکتے.ہم مٹ جائیں گے ہم
ایک ایک کر کے فنا ہو جائیں گے.مگر ہم مکہ کو چھوڑ کر کہیں باہر نہیں جائیں گے.یہ اتنی
عظیم الشان قربانی ہے کہ یقینا اس کی مثال دنیا کی تاریخ میں نہیں مل سکتی.بہر حال اسی طرح مکہ میں ہوتا چلا گیا یہاں تک کہ ہاشم بن عبد مناف جو رسول کریم ملایم
کے پڑدادا تھے ان کا وقت آگیا.جب انہوں نے یہ حال دیکھا تو سمجھا کہ اس طرح تو قوم فنا ہو
جائے گی.انہوں نے لوگوں کو جمع کیا اور ان میں تقریر کی کہ جو طریق تم نے ایجاد کیا ہے یہ اپنی
ذات میں جہور کے لحاظ سے تو بڑا اچھا ہے مگر اس طرح وہ کام پورا نہیں ہو گا جس کے لئے تم
لوگ مکہ میں آئے ہو.اگر یہی طریق جاری رہا اور تم میں سے اکثر مر گئے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مکہ
خالی ہو جائے گا.بے شک جوش وخروش اور عزم کی پختگی کے لحاظ سے یہ کام ایسا شاندار ہے کہ
اس
کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے.مگر عقل کے لحاظ سے یہ اچھا نہیں.کوئی ایسی تدبیر
ہونی چاہئے کہ ہم سب لوگ مکہ میں بھی رہیں اور اس قسم کی موت بھی ہم میں واقعہ نہ ہو.غالباً ان کے ذہن میں یہ خیال بھی آیا ہوگا کہ اس طریق کو جاری رہنے دیا گیا تو دوسری
قوموں پر اس کا برا اثر پڑے گا اور وہ کہیں گی یہ لوگ خدا کے لئے مکہ میں بیٹھے ہوئے تھے مگر
بھوکے مر گئے.پس اس طرح خدا کا احترام کم ہو جائے گا اور لوگ یہ سمجھیں گے کہ خدا تعالیٰ کی
خاطر قربانی کرنے کا نتیجہ اچھا نہیں ہوتا.ہمیں اپنے آپ کو اس طرح رکھنا چاہئے کہ ہمارا عزاز
942
Page 951
دنیا میں قائم ہو اور دوسرے عرب قبائل سے ہماری حالت اچھی ہو.مکہ والوں نے باشم کی بات
سن کر کہا آپ جو تدبیر بتائیں ہم اسے ماننے کے لئے تیار ہیں.آپ نے فرمایا میری تجویز تو
یہ ہے کہ ہم لوگ رہیں تو مکہ میں ہی مگر اپنی حالت کو بہتر بنانے کے لئے تجارت شروع کر
دیں.یوں بھی اپنی ذاتی اغراض کے لئے ہم بعض دفعہ سفر کر لیتے ہیں.اگر آئندہ ہم بعض سفر
محض تجارت کی خاطر کریں تو اس سے ہماری گری ہوئی حالت بہت کچھ سدھر جائے گی اور
ہماری پریشانی دور ہو جائے گی.زراعت کی تجویز آپ نے اس لئے نہ کی کہ مکہ میں زراعت کی
کوئی صورت نہیں تھی.دوکانداری کی تجویز آپ نے اس لئے نہ کی کہ دوکاندار کے لئے
ضروری ہوتا ہے کہ وہ رات دن دوکان پر بیٹھا رہے.آپ نے سمجھا کہ اگر لوگوں نے
دوکانداری شروع کر دی تو خدمت کعبہ کا وہ موقع جو اب انہیں مل رہا ہے اس سے وہ محروم ہو
جائیں گے.چنانچہ آپ نے یہ تجویز کی کہ قوم کا روپیہ لے کر ہر سال دو سفر کئے جائیں.ایک
سفر سردی کے موسم میں کیا جائے جو یمن کی طرف ہو اور ایک سفر گرمی کے موسم میں کیا جائے
جو شام کی طرف ہو.شام بوجہ سرد مقام ہونے کے گرمی کے سفر کے لئے موزوں تھا اور یمن
بوجه گرم مقام ہونے کے سردی کے سفر کے لئے موزوں تھا.آپ نے تجویز کیا کہ ہر سال
اہل مکہ کے نمائندہ قافلے یہ دو سفر محض تجارت کی غرض سے کیا کریں اور تجارت بھی قوم کے لئے
کریں.اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہاشم بن عبد مناف نے دنیا میں یا کم سے کم عرب میں سب
سے پہلے کمپنی سسٹم جاری کیا ہے.یوں تو تاجر دنیا میں ہمیشہ تجارت کیا ہی کرتے ہیں.زید
تجارت کی غرض سے باہر جاتا اور سودا لے کر آجاتا ہے تو پھر اسے زیادہ مہنگے داموں پر وہ
فروخت کر دیتا ہے.مگر یہ کہ سفر کسی فرد کا نہ ہو بلکہ قومی طور پر تمام قبیلہ کا مشترکہ سرمایہ لے کر
سفر کیا جائے اس کی ابتدا کم سے کم عرب میں ہاشم بن عبد مناف سے ہی ہوئی ہے.لوگوں نے
کہا بہت اچھا ہمیں منظور ہے.چنانچہ قافلے جانے لگے.جب بھی کوئی قافلہ جاتا تو ہر
شخص دس بیس پچاس یا سو روپیہ جتنا دینا چاہتا قافلہ والوں کے سپرد کر دیتا.پھر ان میں سے.943
Page 952
ایک کورئیس بنا دیا جاتا.اور باقی لوگ اہل مکہ کی طرف سے نمائندہ بن کر اس سفر پر روانہ ہو
جاتے.اُمراء جن کی حالت کچھ اچھی تھی وہ بعض دفعہ تجارت کی غرض سے اپنے غلام بھی ان
سفروں میں بھیج دیا کرتے تھے.ان کا طریق تجارت یہ تھا کہ وہ مکہ سے روانہ ہوتے وقت ایسی
چیزیں اپنے ساتھ لے لیتے تھے جو ان کی نظروں میں متبرک ہوتی تھیں اور جہاں جہاں عرب
قبائل میں سے گزرتے وہاں مکہ کے تبرکات انہیں دیتے جاتے.مثلاً آب زمزم کے کچھ
مشکیزے بھر کر اپنے ساتھ رکھ لیتے.چونکہ عرب قبائل کو خانہ کعبہ سے بہت عقیدت تھی اس
لئے جب انہیں گھر بیٹھے آب زمزم میسر آجاتا یا اسی طرح کی بعض اور چیزیں مل جاتیں تو وہ بہت
خوش ہوتے اور قریش کو نہایت ادب اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے.اسی طرح اور بھی کئی چیزیں
وہ اپنے ساتھ رکھ لیتے تھے.مثلاً مکہ میں لوہارے کا کام اچھا ہوتا ہے وہ لوہے کی تیار شدہ
چیزیں لے لیتے.اسی طرح کھجور میں اپنے ساتھ رکھ لیتے اور یہ سب چیزیں رستہ میں فروخت
کرتے جاتے.پھر جہاں عرب قبائل میں ٹھہرتے اور دیکھتے کہ وہاں کوئی چیز ایسی ہے جو شام
میں اچھے داموں پر فروخت کی جاسکتی ہے تو وہ ان قبائل سے ایسی چیزیں خود خرید لیتے اور شام
میں جا کر فروخت کر دیتے.پھر جب شام سے آتے تو وہاں سے دو قسم کا مال خرید لیتے.کچھ تو مکہ
والوں کے لئے اور کچھ راستہ میں آنے والے عرب قبائل میں فروخت کرنے کے لئے.اس
طرح ان کو نفع بھی حاصل ہوتا اور شام اور دوسرے عرب علاقوں کا مال بھی مکہ میں آجا تا.اسی
طرح سردیوں میں وہ یمن کا سفر کیا کرتے تھے.مگہ اور یمن کے درمیان بھی بڑا لمبا فاصلہ تھا
اور اس راستہ پر بھی مختلف عرب قبائل آباد تھے.اس سفر میں بھی وہ تمام لوگوں کو مکہ کے تحائف
دیتے اور ان سے عمدہ عمدہ چیزیں خریدتے ہوئے یمن پہنچ جاتے اور یمن میں تمام مال فروخت
کر کے وہاں کی مصنوعات اور غلہ وغیرہ کچھ مکہ والوں کے لئے اور کچھ رستہ کے عرب قبائل میں
فروخت کرنے کے لئے لے آتے.نتیجہ یہ ہوا کہ چند سال میں ہی مکہ کی دولت سارے عرب
سے زیادہ ہوگئی.944
Page 953
ان
کا یہ بھی طریق تھا کہ جب قافلہ واپس آتا تو ہر آدمی جس کا اس تجارت میں حصہ ہوتا تھا وہ
اپنا آدھا حصہ غرباء کے لئے نکال دیتا تھا.مثلاً ایک شخص کو دوسورو پی نفع حاصل ہوا تو سوروپیہ
وہ خود رکھ لیتا تھا اور سو روپیہ قومی فنڈ میں دے دیتا تھا.اس طرح غرباء کے گزارہ کے لئے
ایک کافی رقم نکل آتی تھی.فرض کرو ایک دفعہ قافلہ گیا اور اسے ایک لاکھ روپیہ نفع حاصل ہوا تو
پچاس ہزار روپیہ اسی وقت غرباء میں تقسیم کرنے کے لئے علیحدہ کر لیا جاتا تھا.اس طرح ایک
قلیل مدت میں غرباء کی حالت بھی بہت بہتر ہو گئی.چنانچہ ایک عرب شاعر مکہ والوں کی
تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ مکہ کے لوگ ایسے اعلیٰ درجہ کے اخلاق کے مالک ہیں کہ وہ
اپنا آدھا مال غرباء میں بانٹ دیتے ہیں اور اس طرح ان کے غریب بھی امیر کے برابر ہو جاتے
ہیں.یہ تو ایک مبالغہ ہے کیونکہ سارے مکہ میں زیادہ سے زیادہ پندرہ بیس مالدار ہوں گے اور
سارے شہر کی آبادی پندرہ بیس ہزار ہو گی.وہ اپنا نصف نصف مال تقسیم بھی کریں تو بہت تھوڑا
رو پیدلوگوں کو مل سکتا تھا.لیکن بہر حال اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ان سفروں کے نتیجہ میں
ان کی حالت اچھی ہو گئی اور وہ موت جو محض فاقوں کی وجہ سے ان پر آرہی تھی اس سے
انہوں نے نجات حاصل کر لی.اس کے بعد قریش اس طریق پر برابر عمل کرتے رہے یہاں
تک کہ اسلام آگیا اور مکہ والے باقی سارے عرب سے زیادہ امیر ہو گئے اور دوسروں سے زیادہ
معزز بھی ہو گئے.ان مذکورہ بالا واقعات سے دو باتیں نکلتی ہیں.ایک تو یہ کہ بنو اسمعیل وعدہ ابراہیمی کی
پابندی کرتے ہوئے مکہ میں بیٹھ نہیں رہے بلکہ شروع میں ہی وہ مکہ چھوڑ کر ادھر اُدھر پھیل گئے
تھے.قصی بن کلاب نے تحریک کر کے دوبارہ انہیں مکہ میں بسایا.پس جولوگ ان کے کہنے پر
مکہ میں آبسے ان کو قریش کہا جانے لگا.یعنی وہ لوگ جو پہلے بکھرے ہوئے تھے مگر پھر قصٹی کی
تحریک پر دوبارہ مکہ میں جمع ہوئے.دوسری بات ان واقعات سے یہ کھلتی ہے کہ مکہ میں بسنے کی وجہ سے یہ لوگ غریب ہو گئے
945
Page 954
تھے.ہاشم جو رسول کریم علیہ کے پڑدادا تھے انہوں نے تحریک کی کہ یہ لوگ شام اور یمن کا
سفر کیا کریں تا کہ ان کی حالت اچھی ہو.اگر ہم عربوں کی ایک نسل کی عمر 30 سال فرض کر لیں تو یہ تحریک رسول کریم علمی کی
پیدائش سے کوئی سوا دو سو سال پہلے شروع ہوئی ہے.حضرت ابراہیم علیہ السلام اور رسول کریم
لم کے زمانہ کے درمیان کوئی 22-23 سو سال کا فرق تھا....اس میں سے یہ سوا دوسو
سال نکال دیں تو باقی دو ہزار سال رہ گئے.یہ دو ہزار سال کا زمانہ ایسا تھا جس میں قوم اپنا
فرض بھولی رہی.دنیا میں یہ قاعدہ ہے کہ جوں جوں اوپر کی نسل کی طرف جائیں ماں باپ کی یاد
اولاد کے دلوں میں زیادہ قائم ہوتی ہے اور جوں جوں نیچے کی طرف آئیں یہ یاد کم ہوتی چلی جاتی
ہے.اس قاعدہ کے مطابق حضرت اسمعیل علیہ السلام کے زمانہ کا قرب جس نسل کو حاصل تھا
اسے قدرتاً وہ وعدے زیادہ یاد ہونے چاہئے تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئے.کیونکہ دنیا میں طریق یہی ہے کہ باپ کو بیٹا زیادہ یادرکھتا ہے.پوتا اس کی یاد کو کم کر دیتا ہے
اور پڑپوتا اس کی یاد کو اور بھی کم کر دیتا ہے یہاں تک کہ چار پانچ پشت میں تو اولاد اپنے دادا
پڑدادا کو بالکل ہی بھول جاتی ہے.اور اگر اس سے بھی زیادہ عرصہ گزر جائے تو انہیں کچھ بھی یاد
نہیں رہتا.چنانچہ تمام بڑی بڑی قوموں کو دیکھ لو سب میں یہی کیفیت نظر آئے گی.مثلاً
رسول کریم علی کی بیٹی حضرت فاطمہ کی اولاد نے جو ابتدا میں قربانیاں کیں وہ کتنی حیرت انگیز
ہیں.مگر اب سادات کو دیکھ لو ان کی کیا حالت ہے.ان میں سے اکثر ایسے ملیں گے جو اسلام
سے کوسوں دور ہیں حالانکہ وہ رسول کریم ملی کی بیٹی کی اولاد ہیں.غرض طبعی طریق کو اگر مد نظر رکھا جائے تو شروع زمانہ میں حضرت ابراہیم اور حضرت
اسمعیل علیہما السلام کا اثر ان کی قوم پر زیادہ ہونا چاہئے تھا اور دوہزار سال کے بعد تو ایسی جاہل اور
ان پڑھ قوم میں سے ان کا ذکر بالکل مٹ جانا چاہئے تھا.مگر ہوا یہ کہ عین دوہزار سال کے بعد
پھر ان میں ایک تحریک پیدا ہوئی اور وہ اپنے دادا کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے مگہ
946
Page 955
میں آبسے.وہ بھوکے بھی رہے، وہ ننگے بھی رہے، وہ تکلیفیں بھی برداشت کرتے رہے مگر
انہوں نے مکہ کو نہ چھوڑا.اب سوال یہ ہے کہ وہ کیا اتفاق تھا جس نے دو ہزار سال کے بعد قوم میں خانہ کعبہ کے
گرد بسنے کا پھر احساس پیدا کر دیا.علم النفس کے ماتحت اگر ہم غور کریں تو دو ہزار سال کے بعد یہ
ذکر قوم میں سے بالکل مٹ جانا چاہئے تھا.مگر ہوا یہ کہ دوہزار سال کے بعد یکدم ان میں ایک
شخص پیدا ہوا اور اس نے کہا کہ ہم کو پھر مکہ میں جمع ہو جانا چاہئے اور اولاد اسمعیل میں سے ایک
قبیلہ باوجود ہر قسم کے مخالفانہ حالات کے مکہ میں بیٹھ جاتا ہے اور خانہ کعبہ کی خدمت اور مکہ کی
حفاظت کا کام اپنے ذمہ لے لیتا ہے اور پھر یہ لوگ اس کام کو اتنی محبت اور اتنے پیار سے سر
انجام دیتے ہیں کہ وہ بھوکے مرتے ہیں.ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے بچے تڑپ تڑپ کر
جان دیتے ہیں.ان کی بیویاں اور ان کی بیٹیاں مرتی ہیں.مگر وہ مکہ کو چھوڑ نے کا نام نہیں لیتے.اتنا شدید احساس دو ہزار سال گزرنے کے بعد ان لوگوں میں کیوں پیدا ہوا؟ اور پھر اسی قبیلہ کے
دل میں یہ خیال کیوں پیدا ہوا جس میں سے محمد رسول اللہ صل العلیم نے پیدا ہونا تھا.ایک معمولی غور سے یہ بات سمجھ میں آسکتی ہے کہ یہ قدرت کی ایک انگلی تھی جس نے قوم کو
اشارہ کیا کہ جس بات کے لئے تمہارے باپ دادا نے اس مکہ کو آباد کیا تھا اس کا وقت اب
بالکل قریب آرہا ہے.جاؤ اور مکہ میں رہو.ورنہ یہ اتفاق کس طرح ہوسکتا ہے کہ دو ہزار سال
ادھر اُدھر پھرنے کے بعد ایک بڑی قوم کا صرف وہی ٹکڑا نگہ میں جمع ہوتا جس میں سے آنے
والے موعود نے پیدا ہونا تھا.دشمن کہہ سکتا ہے کہ محمد رسول اللہ علی ایم نے نعوذ باللہ جھوٹا دعویٰ
کر دیا.مگر سوال یہ ہے کہ آخر یہ کیا بات ہے کہ اس جھوٹے کی آمد سے پہلے تمام قوم چاروں
طرف سے اکٹھی ہو کر مکہ میں آجاتی ہے اور اس لئے آتی ہے کہ ہمارے دادا ابراہیم نے کہا تھا
کہ تم اس مقام پر رہو اور اسے آباد رکھو کہ یہ عالمگیر مذہب کا مرکز بنے والا ہے.یہ عظیم الشان
تغیر جو یکدم بنو اسمعیل میں پیدا ہوا اور جس نے ان میں تہلکہ ڈال دیا بتاتا ہے کہ یہ سب کچھ
947
Page 956
اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس وعدہ کے مطابق ہوا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیا گیا تھا.حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی کہ رَبِّنَا وَابْعَثُ فِيهِمْ رَسُولًا
مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمُ ايْتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَب وَالْحِكْمَةَ وَيُزَلِيْهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ
الْحَكِيمُ (البقرة (130) اے میرے رب ان مکہ والوں میں ایک رسول مبعوث فرما جو انہی
میں سے ہو.وہ انہیں تیری آیات پڑھ پڑھ کر سنائے.تیری کتاب کا علم ان کو دے.حکمت کی
باتیں ان کو سکھائے.اور ان کے نفوس کا تزکیہ کرے.اس دعائے ابراہیمی سے ظاہر ہوتا تھا
کہ وہ رسول مگہ میں آئے گا اور مکہ کے رہنے والوں سے سب سے پہلے کلام کرے گا.اگر مکہ آباد
نہ ہوتا تو وابعث فيهم رسُولا کی دعا کس طرح پوری ہوتی اور وہ کون سے لوگ تھے جن میں یہ
رسول مبعوث ہوتا.اسی طرح ابراہیم نے کہا تھا کہ وہ انہیں کتاب اور حکمت سکھائے.اگر مکہ
آباد نہ ہوتا تو وہ کون لوگ تھے جن کو کتاب اور حکمت سکھائی جاتی.پھر حضرت ابراہیم
علیہ السلام نے کہا تھا کہ وہ رسول ان کو پاک کرے.اگر وہاں کوئی آدمی ہی نہ ہوتا تو اس
رسول نے پاک کن کو کرنا تھا.اگر مکہ آباد نہ ہوتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو یہ چار
دعائیں کی تھیں ان میں سے ایک بھی پوری نہ ہو سکتی.پس یہ اتفاق نہیں تھا بلکہ جو کچھ ہوا الہی
سکیم اور اس کے منشاء کے مطابق ہوا.دشمن کہہ سکتا ہے کہ محمد رسول اللہ علیم نے نعوذ باللہ
جھوٹا دعویٰ کر دیا مگر اس امر کو کون اتفاق کہہ سکتا ہے کہ دوہزار سال تک ایک قوم اِدھر اُدھر
بھٹکتی پھرتی ہے.وہ ابراہیم اور اسمعیل کی تمام پیشگوئیوں کو فراموش کر دیتی ہے مگر جب زمانہ
محمدی قریب آتا ہے تو یکدم اس قوم میں ایک حرکت پیدا ہوتی ہے.وہ کہتی ہے ہم سے یہ کیا
بے وقوفی ہوئی کہ ہم ادھر اُدھر پھرتے رہے.ہمارے دادا نے تو ہم سے کہا تھا کہ مکہ میں
رہو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو.ہمارے دادا نے تو کہا تھا کہ تمہاری تمام ترقی مکہ میں رہنے
سے وابستہ ہے.مگر ہم کہیں کے کہیں پھرتے رہے.اور وہ پھر مکہ میں آکر بس جاتی ہے.اس
لئے نہیں کہ مکہ میں کوئی کارخانہ کھل گیا تھا.اس لئے نہیں کہ وہاں تجارتیں اچھی ہوتی تھیں.948
Page 957
اس لئے نہیں کہ وہاں زراعت اچھی تھی.بلکہ صرف اس لئے کہ ابراہیم نے انہیں ایک بات
کہی تھی اور وہ اس پر عمل کرنے کے لئے وہاں اکٹھے ہو گئے.پس یہ اتفاق نہیں بلکہ جو کچھ ہوا
اللہ تعالیٰ کے منشاء اور اس کے ازلی فیصلہ کے مطابق ہوا.پھر میرے نزدیک بالکل ممکن ہے کہ اس اجتماع میں یہودی اور نصرانی روایات کا بھی
دخل ہو کیونکہ قوم کو دوبارہ سمجھانے والے قصی تھے جن کے تعلقات نصاری اور یہود سے تھے.تعجب نہیں کہ جب یہودیوں اور عیسائیوں میں یہ چرچے شروع ہوئے ہوں کہ نبی مختون کی آمد
کا وقت قریب ہے اور یہود ونصاریٰ کے علماء سے انہوں نے سنا ہو کہ موعود نبی عرب میں ظاہر
ہونے والا ہے تو اپنی قومی روایات کو ملا کر انہوں نے یہ نتیجہ نکالا ہو کہ اگر موعود نبی عرب میں آیا
تو پھر مکہ میں ہی آئے گا...اور ان کے دل میں یہ خیال آیا ہو کہ خدا تو ہمارے گھر میں نبوت کا
چشمہ پھوڑنے والا ہے اور ہم ادھر اُدھر بھٹکتے پھرتے ہیں اور اسی بناء پر انہوں نے اپنی قوم کو
ی نصیحت کی ہو کہ آؤ اور مکہ میں اکٹھے ہو جاؤ تا کہ آنے والے ظہور سے فائدہ اٹھا سکو.میں نے اوپر کہا تھا کہ خدا کی انگلی نے انہیں اشارہ کیا اور وہ مگہ میں جمع ہو گئے.لیکن
اب میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے یہود اور نصاریٰ سے آنے والے نبی کی باتیں سنیں اور جب
انہیں معلوم ہوا کہ عرب میں ایک نبی آنے والا ہے تو اپنی قومی روایات اور حضرت ابراہیم
علیہ السلام کے وعدے ملا کر انہوں نے یہ نتیجہ نکال لیا ہو کہ وہ نبی مکہ میں پیدا ہونے والا ہے.بظاہر ان دونوں میں اختلاف نظر آتا ہے لیکن در حقیقت کوئی اختلاف نہیں.اس لئے کہ اگر
انہوں نے یہود اور نصاری سے سن کر ایسا کیا تب بھی یہود اور نصاری نے جو کچھ بتایا وہ خدائی
پیشگوئیاں تھیں اور خدائی پیشگوئیاں بھی قدرت کی انگلی ہوتی ہیں جو بنی نوع انسان کی راہنمائی
کرتی ہیں.اور اگر انہوں نے ان پیشگوئیوں کو نہیں سنا تب بھی یہ خدائی انگلی اور اس کی قدرت کا
ایک زبردست ہاتھ تھا کہ جس بات کا انہیں دو ہزار سال تک خیال نہ آیا وہ نبی عرب کے ظہور
سے سوا دوسو سال پہلے انہیں یاد آگئی اور ایسی یاد آئی کہ ہزاروں تکالیف کے باوجود وہ مکہ میں
949
Page 958
آ کر بس گئے.پس اگر وہ یہود و نصاریٰ کی باتیں سن کر آئے تب بھی اور ا گر وہ خود بخود آئے تب
بھی، جو کچھ ہوا قدرت کے اشارہ کے ماتحت ہوا اور اس طرح اپنی قوم کو وہاں جمع کر کے وہ
خدائی تدبیر کا آلہ کار بن گئے.باشم کے زمانہ میں شام اور یمن کی طرف تجارتی قافلے جاری کرنے کی سکیم بھی اسی الہی
تدبیر کی ایک کڑی معلوم ہوتی ہے.یمن میں اس وقت مسیحیت پھیلنی شروع ہو گئی تھی اور شام
میں تو مسیحیت غالب آچکی تھی.شام سے بھاگ کر یہودی شمالی عرب میں آگئے تھے.اسی
طرح وہ یمن میں بھی چلے گئے تھے.یمن کا ایک حمیری بادشاہ جس نے بیس ہزار عیسائیوں کو
زندہ جلا دیا تھا اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ یہودی ہو گیا تھایا یہودیوں کی طرف مائل تھا.یہ اس امر کا ثبوت ہے کہ یہودی شام سے بھاگ کر یمن میں چلے گئے تھے اور یہی قومیں تھیں
جنہوں نے آئندہ زمانہ میں اسلام سے نگر لینی تھی.چنانچہ پہلے یمن کا واقعہ ہوا.یعنی ابر ہہ وہاں
سے آیا اور اس نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا.اس کے بعد جب اسلام پھیلا تو شام کے عیسائیوں نے
اسلام سے مقابلہ شروع کر دیا.پس اللہ تعالیٰ نے اپنی کمال حکمت کے ماتحت یہود اور نصاریٰ
کے حالات سے مکہ والوں کو باخبر رکھنے کے لئے یہ شتاء وصیف کے سفر تجویز کرا دئیے.روزی کمانا اور چیز ہے مگر اس غرض کے لئے دو خاص ملکوں کو چن لینا اور چیز ہے.ورنہ ہاشم بن
عبد مناف ان کو یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ تجارتیں کیا کرو.مگر ان کا ایسی سکیم بنانا جس سے مکہ والوں
کا یمن اور شام سے تعلق پیدا ہو جائے اور پھر اللہ تعالیٰ کا اس سورۃ کو آلمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ
بِأَصْبِ الْفِيْل کے بعد رکھنا صاف بتاتا ہے کہ یہ جو کچھ ہوا لہی سکیم کے ماتحت ہوا.اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ انہیں اس طریق پر کام کرنے کے نتیجہ میں روزی بھی مل جائے اور
انہیں شام اور یمن کے حالات بھی معلوم ہوتے رہیں جن سے کسی زمانہ میں ان کی فکر ہوئی تھی.چنانچہ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں ان میں سے ایک کی فکر اسلام کی بعثت سے پہلے ہوئی اور ایک کی
نگر رسول
کریم علیم کی بعثت کے بعد ہوئی.950
Page 959
دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ یمن اور شام میں عیسائی رہتے تھے اور عیسائیوں سے بڑی
کثرت کے ساتھ انہیں ایسی خبریں مل سکتی تھیں جن میں آنے والے موعود کی خبر دی گئی تھی.اسی
طرح یہود بھی ان مقامات پر رہتے تھے اور ان سے بھی آنے والے ظہور کے متعلق بہت سی
خبریں معلوم ہوسکتی تھیں.پس ان دونوں سفروں سے مکہ والوں کو یہودیوں اور مسیحیوں سے
میل ملاپ کا موقعہ ملتا تھا اور پرانے وعدے اِس ان پڑھ قوم کے دلوں میں تازہ ہوتے رہتے
تھے اور اس طرح ان کی توجہ زیادہ سے زیادہ خانہ کعبہ سے تعلق رکھنے والے مامور کی طرف
پھرتی تھی.یہ لازمی بات ہے کہ جن لوگوں کے کانوں میں متواتر اس قسم کی باتیں پڑتی رہیں ان پر ایک
قسم کا رعب پڑ جاتا ہے اور وہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ کوئی بات ضرور ہے.چنانچہ جب وہ یہود
اور نصاریٰ سے متواتر اس قسم کی باتیں سنتے تو وہ بھی یہ سمجھنے لگ جاتے کہ اب ضرور کسی نے آنا
ہے اور اس طرح ان کی باتوں سے ان کے دلوں پر ایک چوٹ لگتی.ان کے کفر پر ایک کاری
ضرب لگتی اور ان کی بے دینی کی دیوار میں شگاف پڑ جاتا.وہ جوں جوں سفر کرتے آنے والے
ظہور کے متعلق متواتر یہود اور نصاریٰ سے پیشگوئیاں سنتے اور پھر وہ ان پیشگوئیوں کو مکہ میں آکر
بیان کرتے.اس طرح ساری قوم میں ایک حرکت سی پیدا ہو گئی اور ان میں بھی ایک نبی کی آمد
کا احساس شروع ہو گیا.دوسری طرف اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب شام اور یمن میں مکہ والے
جاتے تو یہودی اور عیسائی بھی سمجھتے کہ ہمیں مکہ والوں کی طرف سے خطرہ ہے ان کے مقابلہ کے
لئے ہمیں ہوشیار ہو جانا چاہئے کیونکہ پیشگوئیاں سب عرب کی طرف اشارہ کرتی ہیں.غرض شتاء وصیف کے ان سفروں میں ایک بہت بڑی غرض اللہ تعالیٰ نے یہ خفی رکھی
ہوئی تھی کہ مکہ کے لوگ یہود و نصاری سے بار بار ملیں اور آنے والے نبی کے متعلق ان سے
پیشگوئیاں سنتے رہیں تا کہ جب اس نبی کا ظہور ہو اس پر ایمان لانا ان کے لئے آسان ہو.چنانچہ
مدینہ کے لوگوں کو رسول کریم اللہ پر ایمان لانے کی توفیق محض یہود سے تعلق رکھنے کی وجہ سے
951
Page 960
ہی ملی.اللہ تعالیٰ بھی قرآن کریم میں اس کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ
يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوا (البقرة 90) یعنی آج یہودی محمد رسول الله علی تعلیم کا انکار کر
رہے ہیں مگر پہلے یہی یہود عربوں کو بتایا کرتے تھے کہ عنقریب ایک نبی آنے والا ہے جس کے
ذریعہ ہمیں اپنے دشمنوں پر فتح حاصل ہو گی.پس اس شمال وجنوب کے سفر کی وجہ سے مکہ کے
ان پڑھ لوگ یہود و نصاریٰ کے علماء سے ملتے اور ان کی آراء سے جو وہ آخری نبی کے بارہ میں
رکھتے تھے واقف رہتے.چنانچہ اس کا ثبوت اس امر سے بھی ملتا ہے کہ احادیث میں آتا ہے
حضرت ابوطالب جب اپنے ساتھ رسول کریم عالم کو شام کے سفر پر لے گئے تو وہاں ایک
پادری نے آپ کو دیکھ کر کہا کہ اس بچے کی خاص نگرانی کرنا.اس میں ایسی علامات پائی جاتی ہیں
شاید یہ بہت بڑا انسان ثابت ہو اور شاید عرب کے بارہ میں جو الہامی کلام ہے وہ اسی کے ذریعہ
سے پورا ہو.اسی قسم کی باتیں مکہ والے ان سفروں میں متواتر سنتے رہتے تھے اور انہیں باتوں کو
اللہ تعالی محمد رسول الله صل تعلیم کی تائید میں ابتدائی دور چلانے کا ایک ذریعہ بنانا چاہتا تھا.پس یہ دونوں سفر در حقیقت اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت کے ماتحت تھے.ورنہ وہ قوم جس میں
الہام نہیں پایا جاتا تھا، جس کے پاس کوئی شریعت نہیں تھی، جو متمدن علاقوں سے دور رہنے
والی تھی اس کے لئے یہ کتنی مشکل بات تھی کہ وہ محمد رسول اللہ کے دعوی کو سن کر آپ پر ایمان لے
آتی.مگر ان سفروں کے نتیجہ میں جب وہ لوگ متواتر یہودیوں اور عیسائیوں سے اس
قسم کی باتیں
سنتے تو ان کا اپنا عقیدہ کمزور ہوجاتا اور وہ سمجھتے کہ شاید کچھ بات ہوا اور شاید کوئی آنے والا ہم میں
آہی جائے.پس یہ دونوں سفر اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی حکمت کے ماتحت تھے.اسی وجہ
سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی حالت پر تعجب کرو کہ کس طرح یہ قوم جو مکہ میں آبسی تھی
جو بھو کی مرجاتی تھی مگر مکہ سے باہر نکلنا پسند نہیں کرتی تھی اب باقاعدہ جس طرح نماز فرض ہوتی
ہے،سردی آتی ہے تو یمن کی طرف چل پڑتے ہیں.گرمی آتی ہے تو شام کی طرف چل پڑتے
ہیں.یہ سفروں کی محبت ان کے دلوں میں آخر کس نے پیدا کی ہے.صرف ہم نے پیدا کی
952
Page 961
ہے.اگر یہ مگہ میں بیٹھے رہتے تو ان کو کچھ بھی پتہ نہ چلتا کہ ہم نے محمد رسول اللہ الیہ کے متعلق
کیا کیا پیشگوئیاں کی ہوئی ہیں.مگر اب ان کے دلوں میں ان سفروں کی ایسی محبت پیدا کر دی گئی
ہے کہ یہ نہایت با قاعدگی کے ساتھ گرمیوں میں شام کا اور سردیوں میں یمن کا سفر کرتے
ہیں.یمن میں جاتے ہیں تو وہاں کے لوگوں سے اس قسم کی باتیں سنتے ہیں کہ ایک نبی آنے والا
ہے اور شاید وہ عرب سے ہی پیدا ہو.شام میں جاتے ہیں تو وہاں کے لوگوں سے سنتے ہیں کہ
ایک نبی آنے والا ہے اور شاید وہ عرب سے ہی پیدا ہو.اس طرح ان کے کانوں کو ہم نے ان
پیشگوئیوں سے آشنار کھا جو محمد رسول اللہ علیم کے ظہور کے متعلق تھیں تا کہ آپ کے دعوی کو
سنتے ہی وہ یکدم انکار نہ کر دیں اور واقعہ میں مکہ والوں کو کلام الہی سے جتنا بعد تھا اس کو دیکھتے
ہوئے یہ کتنا مشکل تھا کہ وہ رسول کریم علیہ کی آواز سن کر آپ پر ایمان لا سکتے.یہ انہی
پیشگوئیوں کے سننے کا نتیجہ تھا کہ جب رسول کریم علیم نے یہ دعویٰ فرمایا تو مکہ میں سے ہی کچھ
لوگ ایسے کھڑے ہو گئے جو فوراً آپ پر ایمان لے آئے....حمد پس مکہ والوں کے یمن اور شام کے سفر در حقیقت محمد رسول اللہ علیم کی بعثت کے
لئے بطور ارہاص تھے اور اس ذریعہ سے وہ محمد رسول اللہ صل العلیم پر ایمان لانے کے لئے تیار
کئے جا رہے تھے.یہی وجہ ہے کہ سورہ الم ترَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَب الْفِيْلِ کے معا بعد
خدا تعالیٰ نے سورۃ ایلاف کو رکھا ہے.لا يلف قريش الفِهِمْ رِحْلَةَ الشَّتَاءِ وَالضَّيْفِ
مختلف محذوفات کی وجہ سے جو لام سے پہلے نکالے گئے ہیں اور ایلاف کے مختلف
معنوں کی وجہ سے اس آیت کے کئی معنے ہوں گے جو قریباً ایک دوسرے سے تعلق رکھنے والے
ہوں گے.پہلا مطلب اس کا یہ ہوا کہ ہم نے قریش کے دل میں سردی گرمی کے دونوں سفروں کی
محبت پیدا کرنے کے لئے ابرہہ کے لشکر کو تباہ کر دیا اور انہیں بھوسے کی طرح اڑا دیا.اس میں
953
Page 962
اس طرف اشارہ ہے کہ خدا تعالیٰ ان دونوں سفروں کو قائم رکھنا چاہتا تھا.ان معنوں کے رُو
سے خدا تعالیٰ کا زور دونوں سفروں کے قیام پر ہے.یعنی دونوں سفروں کا قیام الہی سکیموں کا
ایک حصہ تھا.اور چونکہ الہی حکمت چاہتی تھی کہ یہ دونوں سفر قائم رہیں اس لئے اس نے ابرہہ
کے لشکر تباہ کر دیا.مگر اس کے یہ معنے نہیں کہ اسی لئے تباہ کیا.بلکہ اس لئے“ کے معنے ہیں.اور اس لئے اور اسی لئے میں فرق ہوتا ہے.اسی لئے کے معنے ہوتے ہیں کہ یہی اصل مقصد
تھا.مگر اس لئے کے معنے یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ مختلف وجوہ میں سے یہ بھی ایک وجہ تھی.جیسا کہ
میں پہلے بیان کر چکا ہوں اس تباہی کے کئی اسباب تھے جن میں سے ایک یہ بھی تھا.پس یہاں
ہم اس لئے کہیں گے نہ کہ اسی لئے“.میں نے بتایا ہے کہ ان کے سردی گرمی کے سفروں کے قیام کی بڑی وجہ یہ تھی کہ
رسول کریم عالم کے آنے کی پیشگوئیاں یہودیوں اور عیسائیوں میں تو محفوظ تھیں لیکن حضرت
ابراہیم کی پیشگوئیاں مکہ میں محفوظ نہیں تھیں.مکہ والے امتداد زمانہ کی وجہ سے ان پیشگوئیوں کا
اکثر حصہ بھول چکے تھے.اس لئے ضروری تھا کہ ان کو وہ پیشگوئیاں دوسری قوموں کے ذریعہ
سے یاد کروائی جائیں.دوسرے معنے اس کے یہ بنیں گے کہ اس امر پر تعجب کرو کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے
قریش کو سردی گرمی کے سفر پر تیار کر دیا.یعنی ان لوگوں کے دلوں میں سفر کی محبت پیدا کر دی.ان معنوں کے رُو سے ایک دوسرے معنوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے.بے شک ان
معنوں سے اس طرف بھی اشارہ ہے کہ ان کو سردی گرمی کے سفر پر تیار کر دیا اور اس طرح یہ
محمدی دین کی طرف مائل ہو گئے.مگر ایک اور حکمت کی طرف بھی اشارہ کیا ہے اور وہ یہ کہ باشم
نے کہا تھا کہ اگر تم سفروں کے لئے نہ نکلے تو تم بھوکے مرو گے اور دوسری قوموں میں ذلیل ہو
جاؤ گے.اللہ تعالیٰ اسی امر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اس سردی گرمی کے
سفر کی دراصل ہم نے تدبیر کی تھی.اگر یہ سفر نہ ہوتا تو ان میں ایمان تو تھا ہی نہیں صرف قومی
رسم و رواج کی وجہ سے وہ وہاں ٹھہرئے ہوئے تھے.ممکن تھا کہ اگر وہ اسی طرح ایک لمبے
954
Page 963
عرصہ تک بھوکے مرتے چلے جاتے تو تنگ آکر وہ مکہ چھوڑ دیتے.پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ
ہم نے انہیں مکہ میں رکھنے کے لئے یہ تدبیر سجھادی ور نہ دنیا کی تاریخ پر اگر غور کیا جائے تو معلوم
ہوتا ہے کہ ہزار ہا قو میں دنیا میں ایسی گزری ہیں جنہوں نے اپنی معاشی ضرورت کے لئے جگہیں
بدلی ہیں.غرض کچھ لوگ مکہ والوں میں سے سفروں پر جاتے تھے اور کمائی کر کے لاتے تھے اور
باقی لوگ مکہ میں رہتے.مکہ میں رہنے والوں کی وجہ سے اللہ تعالی قافلہ والوں کے کام میں بھی
برکت پیدا کر دیتا اور اس طرح ان کا بھی گزارہ ہوجاتا اور مکہ والے بھی پلتے رہتے.بہر حال مکہ
والوں کا اکثر حصہ وہیں مکہ میں رہتا تھا.صرف ایک حصہ تجارت کرتا اور وہ جو کچھ کما کر لاتا وہ مگہ
والوں میں بانٹ دیتا.یہ چیز کوئی معمولی چیز نہیں.دنیا میں اس کی کتنی مثالیں پائی جاتی ہیں.اگر
محض ایک انسانی تدبیر تھی تو دیکھنا یہ چاہئے کہ دنیا میں اور کہاں کہاں اس طریق پر عمل ہوتا ہے.یقینا دنیا کی اور کسی قوم نے وہ مثال قائم نہیں کی جو مکہ کے یہ لوگ قائم کر چکے ہیں.ہماری جماعت کو ہی دیکھ لو جب وقف کی تحریک کی جاتی ہے تو ان میں سے کتنے نکلتے
ہیں.دعویٰ یہ ہے کہ وَآخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمُ والی جماعت ہم ہی ہیں، دعویٰ یہ ہے کہ
ہم محمد رسول اللہ کی بعثت ثانیہ کی جماعت ہیں.مگر ان میں سے کتنے دین کے لئے اپنی زندگی
وقف کرتے ہیں.دوسروں کے کام کو دیکھ کر یہ کہنا کہ یہ معمولی بات ہے اور چیز ہے.اور
حقیقت کو مدنظر رکھنا اور بات ہے.کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ مکہ والوں نے جو کچھ کیا وہ ایک
معمولی بات ہے.مگر سوال یہ ہے کہ آج بھی اس مثال پر کتنے لوگ عمل کر سکتے ہیں یا کتنے لوگ
عمل کرنے کے لئے تیار ہوتے ہیں.حقیقت یہ ہے کہ کام کرنا اور چیز ہے اور یہ کہ دینا کہ ایسا کام تو ہر شخص کرسکتا ہے اور بات
ہے.اگر یہ ایسی ہی آسان بات ہے تو دنیا میں اور کسی نے وہ کیوں نہ کر لیا جومکہ والوں نے کیا
تھا.کیا دنیا کے پردہ پر آج کوئی شہر، کوئی قصبہ اور کوئی بستی ایسی ہے جس میں یہ طریق رائج
ہو کہ چند لوگ روزی کما کر لاتے ہوں اور پھر شہر والوں کو کھلا دیتے ہوں اور ان سے کہتے
955
Page 964
ہوں کہ تم اطمینان سے یہاں بیٹھے رہو ہم کمائیں گے اور تمہیں کھلائیں گے.ہم نے تو دیکھا ہے
احمدیوں میں سے بھی بعض ایسے بے حیا اور بے شرم ہوتے ہیں کہ وہ بڑی ڈھٹائی سے کہہ
دیتے ہیں کہ مبلغوں کا کیا ہے وہ تو پیسے لے کر کام کرتے ہیں.ان بے حیاؤں سے کوئی پوچھے
کہ تم بغیر پیسے کے کام نہ کرو.وہ پیسے لے کر کام نہ کریں.تو دین کا کام کون کرے.پھر تو دین
کا خانہ ہی خالی ہو جائے.حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جس طرح تم کما سکتے تھے.اسی طرح وہ بھی کما
سکتے تھے.یہ کہنا کہ غربت کی وجہ سے وہ پڑھ نہیں سکتے تھے یا دنیا میں ترقی نہیں کر سکتے تھے
بالکل جاہلانہ بات ہے.ڈاکٹر اقبال کے باپ بہت ہی معمولی آدمی تھے.ٹوپیاں بنایا کرتے
تھے مگر ان کا ایک بیٹا انجینئر ہو گیا اور دوسر ا علامہ کہلانے لگا.اسی طرح سید احمد صاحب کیا تھے؟
ایک بہت ہی غریب آدمی کے لڑکے تھے مگر ترقی کر کے کہیں کے
کہیں جا پہنچے.پس یہ کہنا کہ
وہ دنیا میں ترقی نہیں کر سکتے تھے اس لئے دین کی طرف چلے گئے، بالکل غلط ہے.دنیا میں
مثالیں موجود ہیں کہ بڑے بڑے غریب لوگوں کی اولادیں بڑے بڑے اعلیٰ مقام تک
جا پہنچیں.پھر سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے دین میں اپنی قابلیت ثابت کر دی ہے تو اسی
طرح وہ دنیوی کاموں میں بھی اپنی قابلیت ظاہر کر سکتا تھا مگر اس نے یہی چاہا کہ وہ خدا کا کام
کرے اور دنیا کے کام کو نظر انداز کر دے.اصل بات یہ ہے کہ محض اس حسد اور غصہ کی وجہ
سے کہ لوگ ہمیں یہ کیوں طعن کرتے ہیں کہ ہم دین کی خدمت نہیں کرتے.بعض لوگ اس
قسم
کے اعتراضات شروع کر دیتے ہیں کہ مبلغوں کا کیا ہے وہ بھی تو نوکری کرتے ہیں.حالانکہ یہ
انتہا درجہ کی بے شرمی کی بات ہے.پس یہ کہنا کہ مکہ والوں نے اگر ایسا کیا تو اپنی حالت کو
درست کرنے کے لئے کیا اس میں قربانی کی کونسی بات ہے، محض واقعات پر غور نہ کرنے کا
نتیجہ ہے.اگر ایسا ہر شخص کرسکتا ہے تو سوال یہ ہے کہ باقی قومیں ایسا کیوں نہیں کرلیتیں اور وہ
کیوں خاموش ہیں؟
حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم اس خوبی کو مکہ والوں کی طرف منسوب کریں تو اس کے معنے یہ بنتے
ہیں کہ وہ سب سے زیادہ نیک جماعت تھی کیونکہ باوجود اس کے کہ وہ کافر تھے، باجود اس کے کہ
956
Page 965
.وہ بے دین تھے انہوں نے وہ کچھ کیا جو کئی مسلمانوں نے نہیں کیا.انہوں نے وہ کچھ کیا جو کئی
احمدیوں نے بھی نہیں کیا.اس رنگ کی قربانی میں احمدی یقیناً مکہ والوں کے برابر نہیں.اور اگر
اس قربانی میں وہ صحابہ سے بھی بڑھے ہوئے تھے، وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر
ایمان لانے والوں سے بھی بڑھے ہوئے تھے تو ہم سوائے اس کے اور کیا کہہ سکتے ہیں کہ
لا يُلفِ قُرَيش الفِهِمُ رِحْلَةَ الشَّتَاءِ وَالصَّيْفِ ایک نشان تھا جو خدا نے دکھایا.ایک
آسمانی تدبیر تھی جس کو خدا تعالیٰ نے ظاہر کیا.مگہ والوں کی یہ ہمت نہیں تھی کہ وہ ایسا کر سکتے.یہ
خدا کا نشان تھا اور اسی خدا کی قدرت کا یہ کرشمہ تھا جو محمد رسول اللہ میم کو مکہ میں مبعوث کرنا
چاہتا تھا اور یہی بات خدا تعالیٰ اس جگہ کہہ رہا ہے کہ مکہ والوں نے باوجود اس کے کہ وہ
بے دین تھے، باوجود اس کے کہ وہ مشرک تھے، باوجود اس کے کہ وہ روحانیت سے عاری
تھے، وہ فعل کیا جو آج تک دنیا کی کوئی قوم نہیں کرسکی.پس وہ فعل مگہ والوں نے نہیں کیا ، وہ
فعل ہم نے ان سے کروایا.وہ صرف ہمارے تصرف اور اثر کا نتیجہ تھا.انہوں نے جو کچھ کیا ہم
اس کی وجہ قومی کیریکٹر قرار نہیں دے سکتے.کیونکہ قومی کیریکٹر کے ہوتے ہوئے بھی بھوک
پیاس کی تکلیف پر لوگ ادھر ادھر بھاگ جایا کرتے ہیں.اسے ہم صرف خدا تعالیٰ کا تصرف
اور خدا تعالیٰ کی تدبیر ہی کہہ سکتے ہیں.مگر اس کے یہ معنے نہیں کہ چونکہ مکہ والوں کا کام ان کا اپنا
کام نہ تھا خدا تعالیٰ کا کام تھا اس لئے ہم اس کی نقل اتارنے کی کوشش نہ کریں.جس حد تک
اس قربانی کی مثال ہم پیش کر سکیں ہمیں پیش کرنی چاہئے.جب تک ہم ایسا نہ کریں ہم دنیا میں
کوئی بڑا انقلاب پیدا نہیں کر سکیں گے.صحابہ نے بے شک دنیا میں انقلاب پیدا کیا لیکن وہ
انقلاب ایسی ہی قربانی کی مثال قائم کرنے کی کوشش سے پیدا کیا.اگر وہ بالکل اس معیار پر
پورے اترتے جو مکہ والوں میں معجزہ کے طور پر اور ظہور محمدی کے پیش خیمہ کے طور پر
اللہ تعالیٰ نے دکھایا تھا تو یقیناً صحابہ اپنی ترقی کے معیار کو اور بھی اونچالے جاتے.وہ اسلام کی
بنیادوں کو اور مضبوط کر دیتے.وہ کفر کی تباہی کو اور بھی مکمل کر دیتے.957
Page 966
ہماری جماعت کے افراد کو بھی غور کرنا چاہئے کہ وہ اس وقت کیا نمونہ پیش کر رہے ہیں.جب وہ غیروں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھو ہماری جماعت کتنی قربانی کر رہی ہے.کس
طرح نوجوان اپنی زندگیاں وقف کر رہے ہیں.کیونکہ وہاں غیر کی طرف سے انہیں عزت مل
رہی ہوتی ہے.مگر جب اندر بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں ان مولویوں کا کیا ہے، یہ تو پیسے لے کر کام
کرتے ہیں.حالانکہ جو کچھ مکہ والوں نے کیا اگر ساری جماعت قربانی کے اس نقطہ تک پہنچ
جائے تو دنیا میں حیرت انگیز طور پر ہماری تبلیغ کا سلسلہ وسیع ہو جائے....مکہ والے بھی آخر اپنی آمد کا نصف قومی کاموں کے لئے دے دیا کرتے تھے.وہ کافر تھے،
وہ بے ایمان تھے، وہ مشرک تھے.مگر وہ سب کے سب اپنی آمد کا نصف اس لئے نکال دیا
کرتے تھے تا کہ وہ غربا میں تقسیم کیا جائے اور مکہ آبادر ہے.ان کے دلوں میں ایمان نہیں تھا
ان کے پاس قرآن نہیں تھا، ان کے سامنے قومی ترقی کا کوئی مقصود نہیں تھا، ان کے سامنے
کوئی اعلی درجے کا آئیڈیل نہیں تھا.محض اتنی بات تھی کہ ٹھنی نے ہم کو کہا ہے کہ ہمارے دادا
ابراہیم نے یہ کہا ہے کہ مگہ میں رہو اس لئے ہم یہاں رہنے کے لئے آگئے ہیں.یہ کتنا چھوٹا سا
آئیڈیل ہے.اس کے مقابلہ میں تمہارا آئیڈیل کیا ہے.تمہارا آئیڈیل یہ ہے کہ تم نے دنیا
فتح کرنی ہے.تم نے دنیا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بادشاہت قائم کرنی ہے.تم نے
دنیا میں خدا کی بادشاہت قائم کرنی ہے.وہ اپنے چھوٹے مقصد کو پورا کرنے کے لئے اپنا
نصف مال لا کر دے دیتے تھے.ان میں سے ہر شخص اپنی آمد کا آدھا حصہ نکال کر کہتا کہ یہ
آدھا حصہ غریبوں کے لئے ہے تا کہ مکہ آباد رہے اور وہ اسے چھوڑ کر ادھر اُدھر نہ جائیں....اگر جماعت مکہ والوں کی قربانی کے برابر قربانی کرنے لگ جائے ، اس سے نصف بھی
کرنے لگ جائے ، اس سے چوتھا حصہ بھی کرنے لگ جائے تو کتنا عظیم الشان کام ہوسکتا
ہے.کتنی تبلیغ وسیع ہوسکتی ہے.خلاصہ کلام یہ کہ دنیا کی تاریخوں میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی کہ صدیوں تک ایک
958
Page 967
قوم کے افراد اپنے لئے تمام ترقی کے راستوں کو روک کر اس گھر کو آباد رکھنے کے لئے جسے وہ
خدا کا گھر سمجھتے ہیں کمائیں آپ اور کھلائیں دوسروں کو.انفرادی مثالیں تو مل جاتی ہیں مگر قومی
طور پر اور متواتر ایک لمبے عرصہ تک اس قسم کی حیرت انگیز قربانی کی کوئی مثال نہیں ملتی.اور جب تک اس قسم کی مثال پیش نہیں کی جائے گی اس وقت تک دنیا کی الجھنوں کا حل بھی پیدا
نہیں ہوگا.یہاں یہ سوال بھی غور طلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ ایلاف کیوں اتاری؟ قریش نے
تو جو کچھ کرنا تھا کر لیا اور محمد رسول اللہ علیم کا زمانہ آ گیا.اس زمانہ میں قریش کی تعریف
کرنے کے تو یہ معنے تھے کہ ان کو اور بھی مغرور کر دیا جائے.وہ کہہ سکتے تھے کہ دیکھا ہمیں کافر
کافر کہتے تھے مگر ہم نے
کتنی قربانی کی.پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا ؟ اسی لئے کہ اللہ تعالیٰ
مسلمانوں کو توجہ دلاتا ہے کہ تم بھی قربانی کا یہ نمونہ پیش کرو.قریش کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس لئے کیا ہے کہ وہ مسلمانوں کو توجہ دلائے کہ کسی زمانہ
میں ایک کافراور مشرک قوم مکہ میں آکر بسی اور اس نے مکہ کو بسانے کے لئے ایسی حیرت انگیز
قربانی کی جس کی مثال دنیا کی تاریخ میں نہیں مل سکتی.بے شک ان میں یہ خوبی خدا تعالیٰ کے
تصرف سے پیدا ہوئی مگر تمہارے ساتھ بھی تو اس کا فضل ہے.تمہیں بھی اس قربانی کو اپنے
سامنے رکھتے ہوئے اسلام کے لئے ایسی ہی قربانی پیش کرنی چاہئے اور ایسا ہی نمونہ دکھانا
چاہئے جیسے ان لوگوں نے دکھایا.پس لا يُلفِ قُرَيْش الفِهِمْ رِحْلَةَ الشَّتَاءِ وَالضَّيْفِ والی آیات یہی سبق دینے کے
لئے نازل ہوئی ہیں کہ خدا اب بھی اصحاب الفیل کا واقعہ دکھانے کے لئے تیار ہے مگر تم بھی تو
قریش والا نمونہ دکھاؤ.اصحاب الفیل والا نشان کن لوگوں کے لئے ظاہر کیا گیا تھا ان
لوگوں کے لئے جنہوں نے سوا دو سو سال تک وہ قربانی کی جس کی مثال دنیا کی تاریخ
میں نہیں مل سکتی.انہوں نے اپنی جانیں دے دیں مگر مگہ نہ چھوڑا.وہ بھوک سے نڈھال ہو کر
959
Page 968
جب موت کے قریب پہنچ جاتے تو اپنا خیمہ اٹھاتے اور مکہ سے باہر چلے جاتے.ان کے
سامنے ان کے بیوی بچے مرجاتے ، ان کے سامنے ان کے بھائی مرجاتے ، ان کے سامنے ان
کی بہنیں مرجاتیں، ان کے سامنے ان کے دوست اور رشتہ دار مر جاتے مگر وہ کسی سے کچھ
مانگتے نہیں تھے.وہ اس تکلیف کی وجہ سے مکہ کو چھوڑتے بھی نہیں تھے.وہ ایک ایک کر کے
مر گئے، مٹ گئے اور فنا ہو گئے مگر انہوں نے مکہ کو نہ چھوڑا.تم بھی یہ قربانی کرو تو خدا تمہارے
لئے بھی اصحاب الفیل والا نشان دکھا دے گا.بلکہ وہ تو غیر مومن تھے ان کے لئے دیر کے بعد
نشان ظاہر ہوا.تم مومن ہو تمہارے لئے یہ نشان جلد ظاہر ہو جائے گا.مگر پہلے قربانی کی مثال تو
ہونی چاہئے.پھر تمہارا بھی حق ہوگا کہ تم خدا سے کہو کہ ہم نے اپنی قربانی تو پیش کر دی ہے اب
تُو بھی ہماری تائید میں اپنا نشان دکھا.لیکن اپنا فرض ادا نہ کرنا اور خدا تعالیٰ سے کہنا کہ وہ وعدہ پورا
کرے یہ کوئی دیانتداری نہیں.خدا تعالیٰ اپنے وعدوں کو پورا کرنے والا ہے اور یقیناً وہ سب
سے زیادہ سچا ہے مگر وہ تبھی نشان دکھاتا ہے جب اس کے مقابلہ میں بندہ بھی قربانی پیش کرتا
ہے....جب تک یہ احساس قائم نہ ہو جائے اور پھر اس احساس کو دوسروں کے اندر قائم نہ کیا
جائے اُس وقت تک کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوسکتی.خلیفہ آخر کیا کر سکتا ہے.دو یا چار یا پانچ لاکھ یا دس لاکھ آدمیوں کو سمجھانے کے لئے
ایک ایک کے گھر پر تو نہیں جاسکتا.اس کا طریق تو یہی ہے کہ لوگ سنیں اور آگے پہنچائیں ، وہ
سنیں اور آگے پہنچائیں.جب تک وہی آگ ان کے دلوں میں بھی نہ لگ جائے ، وہی تڑپ
ان کے دلوں میں بھی پیدا نہ ہو جائے جو خلیفہ وقت کے دل میں لگی ہوئی ہو اور جب تک ایک
ایک احمدی دوسرے کو پکڑ کر یہ نہ کہے کہ تم میں فلاں غلطی ہے اس کی اصلاح کرو اس وقت تک
یہ کام ہو ہی کس طرح سکتا ہے.دیکھو رسول کریم علی لالی نے بھی اپنی وفات کے قریب جب
حجۃ الوداع میں لوگوں کو جمع کر کے ایک تقریر کی تو اس آخری وصیت میں آپ نے یہی کہا کہ
فَلْيُبلغ الشَّاهِدُ الْغَائِب.میں نے بات کہہ دی ہے مگر میری بات سب لوگوں کے
960
Page 969
کانوں تک نہیں پہنچ سکتی.میری بات اسی طرح دوسرے لوگوں تک پہنچ سکتی ہے کہ جو شخص مجھ
سے کوئی بات سنے وہ آگے پہنچائے.وہ اگلا شخص پھر آگے پہنچائے.اور اسی طرح یہ سلسلہ
جاری رہے.یہی قومی ترقی کا گر ہے اسی سے قومیں زندہ ہوتی ہیں اسی سے وہ دنیا میں فتحیاب
ہوتی ہیں.تیسرے معنے اس آیت کے یہ ہوں گے کہ قریش کے دل میں جو سردی گرمی کے
سفروں کی محبت اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے جس کی وجہ سے ان کو بافراغت رزق ملتا ہے اور
متمدن اقوام سے ان کو تعلق پیدا کرنے کا موقع ملتا ہے اس نعمت کو یاد کر کے انہیں خدا تعالیٰ کا
شکر ادا کرنا چاہئے اور خانہ کعبہ کے رب کی عبادت کرنی چاہئے.ان معنوں کے رُو سے اس مضمون کی طرف اشارہ سمجھا جائے گا کہ تمہارے ساتھ جو سلوک
ہو رہا ہے یہ تمہاری وجہ سے نہیں ہو رہا بلکہ خانہ کعبہ کی خدمت کی وجہ سے ہو رہا ہے.کیونکہ
جب کسی کام کا ایک نتیجہ بیان کر دیا جائے تو در حقیقت وہی نتیجہ اس کام کا اصل باعث ہوتا ہے.مثلاً ایک آقا اپنے نوکر کو تنخواہ دیتا ہے.اگر کسی وقت وہ نوکر اس کی نافرمانی کرتا ہے تو آقا اس
سے کہتا ہے ہم تمہیں تنخواہ دیتے ہیں تم کو چاہئے کہ ہماری فرمانبرداری کرو.اس کے دوسرے
لفظوں میں یہ معنے ہوتے ہیں کہ ہم تمہیں اس لئے تنخواہ دیتے ہیں کہ تم ہماری فرمانبرداری کرو.اسی طرح لا يُلفِ قریش کا نتیجہ یہاں فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ نکالا گیا ہے.یعنی ہم نے
ایلاف کیا اور اس کے اچھے سے اچھے نتائج پیدا کئے.پس چاہئے کہ وہ رَبُّ الْبَیت کی
عبادت کریں.یہاں پس“ کا لفظ بتاتا ہے کہ پہلا انعام، پہلا اکرام اور پہلا احترام اسی غرض
سے تھا کہ وہ رَبُّ الْبَيْت کے ساتھ تعلق رکھیں.پس اگر فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ کو
لایلف کے ساتھ لگایا جائے جیسا کہ بہت سے نحوی یہی سمجھتے ہیں.تو اس صورت میں اس کے
معنے یہ ہوں گے کہ تمہارے ساتھ یہ سلوک اس لئے کیا جاتا ہے کہ تم خدا کے گھر کو آباد رکھو اور
اس کا ذکر کیا کرو.اس طرح ان پر واضح کیا گیا ہے کہ تم اپنے متعلق یہ خیال نہ کر لینا کہ یہ سلوک
961
Page 970
تمہاری کسی نیکی یا تمہاری کسی خوبی کی وجہ سے ہے.جیسے یہود میں یہ خیال پیدا ہو گیا تھا کہ وہ
خدا کے محبوب اور پیارے ہیں اس لئے ان سے نیک سلوک کیا جاتا ہے.قرآن کریم میں بھی
اس کا ذکر آتا ہے کہ یہودیوں کا یہ خیال تھا کہ انہیں صرف چند دن سزا ملے گی.بعض کا یہ خیال
تھا کہ ان کو صرف چالیس دن تک سزا ملے گی اور بعض کا یہ خیال تھا کہ انہیں بارہ دن سزا ملے
گی.پھر بعض لوگ یہ خیال کرتے تھے کہ انہیں صرف سات دن سزا ملے گی اور بعض خیال
کرتے تھے کہ یہودی جب دوزخ کے پاس لے جائے جائیں گے تو وہ خدا سے
کہیں گے کہ
اس تعلق کو یاد کر جو تجھے ہمارے باپ ابراہیم سے تھا.اس پر خدا انہیں فور اواپس لوٹا دے گا اور
انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا.اسی قسم کا خیال عربوں میں بھی پیدا ہوسکتا تھا کہ چونکہ ہم
ابراہیم کی نسل میں سے ہیں اس لئے ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ امتیازی سلوک کیا
جا رہا ہے.پس اس آیت میں اس کا ازالہ کیا گیا ہے.م در حقیقت ہر قوم جب بداعمالی کی طرف راغب ہوتی ہے اور اپنی ذمہ داریوں کو بھول
جاتی ہے تو وہ چاہتی ہے کہ کسی ٹوٹکہ کے ذریعہ سے ہی نجات حاصل کر لے.پس اللہ
تعالیٰ فرماتا ہے.لِإِيلافِ قُرَيْشٍ - الفِهِمُ رِحْلَةَ الشَّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ
هذَا الْبَيْتِ (قریش (2-4) ان کو یا درکھنا چاہئے کہ ہم نے ان پر جو احسان کیا ہے یہ خانہ کعبہ
کی وجہ سے کیا ہے.ان کی ذات کی وجہ سے نہیں کیا.ابراہیم کی نسل ہونے کی وجہ سے ہم ان
پر یہ فضل نہیں کر رہے تھے بلکہ اس لئے کر رہے تھے کہ اگر انہیں کھانے پینے کو با فراغت مل
جائے گا تو وہ خدا کا ذکر کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنے اوقات بسر کریں گے تاکہ
آنے والے موعود پر ایمان لانے کے لئے تیار ہوتے رہیں.پس لا یلف کا تعلق اگر فَلْيَعْبُدُوا سے سمجھا جائے تو اس امر پر زور ثابت ہوگا کہ قومی
برتری کوئی چیز نہیں.ان کا یہ خیال کہ یہ سب کچھ ہماری خاطر ہو رہا ہے بالکل غلط ہے.یہ
خانہ کعبہ کی خاطر، خانہ کعبہ کے نبی کی خاطر اور ذکر الہی کو قائم رکھنے کی خاطر ہو رہا ہے.962
Page 971
ہم دیکھتے ہیں کہ اور قو میں تو الگ رہیں آج مسلمان بھی اس مرض میں مبتلا ہیں.جب
اللہ تعالیٰ کسی بڑے آدمی پر اپنا فضل نازل کرتا ہے تو اس کی سنت ہے کہ وہ اس فضل کا سلسلہ
اس کی اولاد کے لئے بھی جاری کرتا ہے مگر آہستہ آہستہ وہ یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ ہم خدا کے
خاص محبوب ہیں.اور خدا کے محبوب کے وہ یہ معنے لیتے ہیں کہ جیسے عاشق کہتے ہیں ہمیں مارلو،
پیٹ لو، دکھ دے لو ہم تمہیں چھوڑ نہیں سکتے.اسی طرح وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خود ہم خدا کو گالیاں دے
لیں، خواہ ہم بے دینی کریں، خواہ ہم اس پر سو سو اعتراض کریں، خواہ ہم اس کو برا بھلا کہیں، خواہ
ہم اس کے کسی حکم کو نہ مانیں، اللہ تعالیٰ ہمارا عاشق ہے وہ ہمیں چھوڑ نہیں سکتا.چنانچہ مختلف
شکلوں اور صورتوں میں لوگوں نے یہ عقیدہ قائم کیا ہوا ہے.حضرت خلیفہ اول رضی اللہ عنہ کی ایک بہن تھیں جو کسی پیر کی مرید تھیں.وہ ایک دفعہ
آپ سے ملنے کے لئے آئی تو آپ نے اس سے کہا بہن تمہیں نماز کی طرف توجہ نہیں تم آخر خدا
کو کیا جواب دو گی؟ اس نے کہا میں نے جس پیر کی بیعت کی ہوئی ہے اس نے مجھے کہہ دیا
ہے کہ چونکہ تم نے میری بیعت کرلی ہے اس لئے اب تمہیں سب کچھ معاف ہے.آپ نے
اپنی بہن سے کہا.بہن اپنے پیر صاحب سے پوچھنا کہ خدا کا حکم کس طرح معاف ہو گیا.نما ز کا
حکم تو خدا نے دیا ہے اور وہ قیامت کے دن اس کا حساب لے گا.آپ کی بیعت کرنے سے یہ
حکم کس طرح معاف ہو گیا ؟ اس نے کہا بہت اچھا جب میں جاؤں گی تو یہ بات ان سے ضرور
دریافت کروں گی.کچھ مدت کے بعد وہ پھر آپ سے ملنے کے لئے آئی تو آپ نے اس سے
پوچھا کہ بتاؤ کہ تم نے اپنے پیر صاحب سے وہ بات دریافت کی تھی؟ اس نے کہا ہاں.میں
اپنے پیر صاحب کے پاس گئی تھی اور ان سے میں نے یہ بات دریافت کی تو وہ کہنے لگے تو
نوردین سے ملنے گئی تھی؟ معلوم ہوتا ہے یہ شرارت تجھے نور دین نے ہی سکھائی ہے.میں نے
کہا کسی نے سکھائی ہو، آپ یہ بتائیں کہ اس کا جواب کیا ہے؟ انہوں نے کہا قیامت کے دن
جس وقت خدا تم سے پوچھے گا کہ تم نمازیں کیوں نہیں پڑھا کرتی تھیں تو تم کہہ دینا کہ میرا
963
Page 972
جواب پیر صاحب سے لیجئے.انہوں نے کہا تھا کہ میری بیعت کر لینے سے اب تمام ذمہ واری
مجھ پر آپڑی ہے، تمہیں نمازیں پڑھنے کی ضرورت نہیں.اس پر خدا کے فرشتے تم کو چھوڑ دیں
گے اور وہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے.میں نے کہا پیر صاحب پھر آپ کا کیا بنے گا؟ اتنے
لوگوں کے گناہ آپ کے ذمہ لگ جائیں گے؟ اس پر وہ کہنے لگے جس وقت خدا ہم سے حساب
لینا چاہے گا تو ہم لال لال آنکھیں نکال کر اس سے
کہیں گے کہ کربلا میں ہمارے دادا امام حسین
کی شہادت کچھ کم تھی کہ اب ہم کو بھی دق کیا جاتا ہے.اس پر خدا اپنی آنکھیں نیچی کر لے گا اور
ہم بھی فوراً جنت میں چلے جائیں گے.دیکھو مسلمانوں کی حالت گرتے گرتے کہاں سے کہاں پہنچ گئی.حالانکہ اور لوگ تو الگ
رہے خدا کے نبی اور رسول بھی جن سے تعلق رکھنے کی بناء پر ہم اپنے آپ کو افضل سمجھتے ہیں ، دن
اور رات کام کیا کرتے تھے.بلکہ نبیوں اور رسولوں کو رہنے دو ہمارا خدا بھی ہر وقت کام کرتا
ہے.آخر خدا کو ہم رب العالمین کہتے ہیں یا نہیں.اور رب العالمین کے کیا معنے ہوتے ہیں؟
یہی کہ وہ ہمیں روٹیاں کھلاتا ہے، ہمارے جانور پالتا ہے، ہمارے بچے پالتا ہے،سمندر کے نیچے
رہنے والی مچھلیوں کو پالتا ہے، پرندے پالتا ہے.اسی طرح اور تمام جانداروں کو پالتا ہے.پھر جب ہم کہتے ہیں خدا نے زمین و آسمان بنایا تو اس کے کیا معنے ہوتے ہیں؟ یہی معنے ہوتے
ہیں کہ ہمارا خدا انجینئر نگ کا کام بھی کرتا ہے، ہسبنڈری کا کام بھی کرتا ہے، زراعت کا کام بھی
کرتا ہے.پھر جب ہم کہتے ہیں اس نے کیمیاوی ترکیبوں سے اس اس طرح چیزیں بنائیں تو
اس کے کیا معنے ہوتے ہیں؟ یہی معنے ہوتے ہیں کہ ہمارا خدا صناع بھی ہے اور ہمارا خدا
سائنسدان بھی ہے.غرض وہ تمام پیشے جو ہم اختیار کرتے ہیں سارے کے سارے خدا کی طرف
منسوب کرتے ہیں.ہم یہ نہیں چاہتے کہ خدا بھی بیٹھ جائے اور وہ کچھ نہ کرے حالانکہ اگر نکتا پین
ہی اصل چیز ہے تو سب سے زیادہ نکما رہنے کا حق خدا تعالیٰ کو ہونا چاہئے.آخر جس نے یہ سب
کچھ پیدا کیا ہے، کیا اس کا یہ حق نہیں کہ وہ اتنا بڑا کام کرنے کے بعد کچھ آرام بھی کرلے.پس
964
Page 973
اگر آرام کرنا ہی بڑا کام ہے تو سب سے زیادہ نما نعوذ باللہ خدا تعالیٰ کو ہونا چاہئے.مگر ہم دیکھتے
ہیں اللہ تعالیٰ بھی کام کرتا ہے، اس کے رسول بھی کام کرتے ہیں، اس کے خلیفے بھی کام کرتے
ہیں اور اس کے مومن بندے بھی کام کرتے ہیں.پھر یہ کیا کہ ایک زمانہ میں انبیاء کی
جماعتیں یہ کہنے لگ جاتی ہیں کہ ہمیں اب کام کرنے کی ضرورت نہیں، ہماری ذمہ واریاں کسی
اور نے اٹھالی ہیں.دراصل یہ قومی تنزل کی علامتیں ہیں اور اس وقت بھی مسلمانوں میں عمل کا
ترک ان کے اسی قومی تنزل کا ثبوت ہے.وہ یہی چاہتے ہیں کہ ان کا بوجھ کوئی اور اٹھالے.مسیح آجائے اور ان کے گھر مال و دولت سے بھر دے.خود انہیں کوئی کام نہ کرنا پڑے.گویا
خدا اور اس کے رسول کا بس یہی کام ہے کہ وہ ڈاکوؤں کی طرح دوسروں کا مال لوٹ کر
مسلمانوں کے حوالے کر دیں اور ان کی بہو بیٹیاں اغوا کر کے مسلمان نوجوانوں کو دیتے چلے
جائیں تا کہ وہ عیاشیاں کریں.یہ کتنی بڑی بد عملی ہے جو غلط اعتقادات کی وجہ سے بعض
مسلمانوں میں پائی جاتی ہے اور کیا ایسی قوم دنیا میں کوئی بھی ترقی کرسکتی ہے؟
حالانکہ جہاں حقیقی محبت ہو وہاں کام زیادہ کیا جاتا ہے اور عام حالات سے زیادہ قربانی پیش
کی جاتی ہے.مشرک لوگ اپنے جھوٹے معبودوں کے لئے کتنے پاپڑ پیلتے ہیں اور طرح طرح
کی تکالیف اٹھا کر انہیں خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں.تو جہاں حقیقی محبت ہوتی ہے وہاں انسان کام زیادہ کرتا ہے.کام کو چھوڑ نہیں دیا کرتا.یہی
بات اللہ تعالى لإيلافِ قُرَيْشٍ - الفِهِمُ رِحْلَةَ الشَّتَاءِ وَالصَّيْفِ.فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا
الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَامَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ.(قریش (2-5) کی آیت میں بیان
فرماتا ہے.یعنی مکہ کے قریش اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان پر مہربانی کی ، ان کے لئے امن
قائم کیا ، ان کی بھوک کو دور کیا اور ان کے لئے ہر قسم کے خطرات کو دنیا سے ہٹا دیا تو ان کو
چاہئے تھا کہ وہ رب البیت کی عبادت بھی کرتے.مگر ایک طرف تو یہ مانتے ہیں کہ خدا نے ان
کے خوف کو ڈور کیا، خدا نے ان کی بھوک کو دور کرنے کے سامان مہیا کئے مگر دوسری طرف یہ
965
Page 974
اتنے نکتے ہو گئے ہیں کہ ہماری عبادت تک نہیں کرتے.ہم نے ان کے دلوں میں جو ایلاف
کیا اور اس کے نتیجہ میں رِحْلةَ الشَّتَاءِ وَالصَّيْف کو قائم کیا.ان کے سفر نفع مند ہو گئے اور ان
کی بھوکیں دُور ہو گئیں.انہیں سوچنا چاہئے کہ یہ سب کچھ کیوں کیا گیا؟ آخر ہماری کوئی غرض
تھی، کوئی مقصد تھا، کوئی وجہ تھی جس کی بناء پر ان سے یہ سلوک کیا گیا تھا.اور وہ وجہ یہی تھی کہ
وہ اس گھر کو آباد رکھیں.پس چاہئے کہ جبکہ ہم نے اپنا حق ادا کر دیا ہے تو یہ بھی اپنا حق ادا کریں
اور عبادت الہی میں اپنا وقت گزاریں.حقیقت یہ ہے کہ یہ سفر بھی لوگوں کے دلوں میں حج کا شوق پیدا کرنے اور انہیں خانہ کعبہ کی
طرف متوجہ کرنے کا ایک بڑا ذریعہ تھے.جیسا کہ میں اوپر بتا چکا ہوں اہلِ عرب کو شروع میں
حج کی طرف کوئی زیادہ توجہ نہیں تھی.پس اللہ تعالیٰ نے ان سفروں کو انہیں حج کی طرف متوجہ
کرنے کا ایک ذریعہ بنا دیا.جب یہ لوگ ان کے گھروں میں جاتے اور ذکر کرتے کہ ہم مکہ
سے آئے ہیں جہاں خانہ کعبہ ہے اور جس کا اس طرح حج کیا جاتا ہے اور جس سے بڑی بڑی
برکتیں حاصل ہوتی ہیں تو تمام عرب میں پراپیگنڈا ہو جاتا اور وہ لوگ جو حج سے غافل تھے ان
کے دلوں میں بھی حج کرنے کی تحریک پیدا ہو جاتی.اس طرح ان کو روزی بھی مل جاتی اور حج
بھی لوگوں میں زیادہ سے زیادہ مقبول ہوتا چلا جاتا.چوتھے معنے اس کے یہ ہیں کہ تعجب ہے مکہ والوں نے اپنے نفسوں پر سردی اور گرمی
کے سفر واجب کر چھوڑے ہیں اور بیٹھ کر خدا تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے.یہ معنے بھی بعض
مفسرین نے کئے ہیں.یعنی تعجب ہے کہ یہ دخل الشَّتَاءِ وَالصَّيْف تو کرتے ہیں مگر عبادت
نہیں کرتے.انہیں چاہئے کہ یہ ان سفروں کو چھوڑ دیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنا وقت
گزار ہیں.مگر جہاں تک میں سمجھتا ہوں یہ معنے درست معلوم نہیں ہوتے.اس لئے کہ ساری تاریخ
اور خود عبارت کی بناوٹ بتا رہی ہے کہ یہاں ان کے اس فعل کو بُرا نہیں کہا گیا بلکہ اسے اچھا
966
Page 975
قرار دیا گیا ہے اور جب ان کے اس فعل کو اچھا قرار دیا گیا ہے تو اس آیت کے یہ معنے
نہیں ہو سکتے کہ وہ سفر کیوں کرتے ہیں.انہیں چاہئے کہ وہ سفر چھوڑ دیں اور بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی
عبادت کریں.پس یہ معنے لفظا اور نحواً تو درست ہیں مگر یہاں چسپاں نہیں ہوتے.دوسرے وہ
یہ سفر اس لئے کرتے تھے کہ روٹی کما کر لائیں اور پھر مکہ والوں میں بانٹیں تا کہ وہ مکہ میں ہی
رہیں، تلاش معاش میں مکہ چھوڑ کر ادھر اُدھر نہ چلے جائیں.اب ان معنوں کو درست تسلیم
کرنے کا تو یہ مطلب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان سے فرماتا ہے کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہئے کہ تم باہر
جاؤ اور مکہ والوں کو کھلاؤ.مگر ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ یہ معنے عقل کے خلاف ہیں.اس لئے اس
آیت کا ہر گز یہ مفہوم نہیں.ان سفروں کی ضرورت تو انہیں موت اور ہلاکت کی وجہ سے پیش آئی
تھی.اگر بلا ضرورت مکہ والے سفر کرتے تو اعتراض کی بات تھی مگر جبکہ ایک اعلیٰ مقصد کے لئے
انہوں نے یہ سفر اختیار کئے تھے تو اس آیت کے یہ معنے کرنا کہ وہ سفر کیوں کر رہے ہیں ان
سفروں کو چھوڑیں اور بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں کسی طرح بھی درست معلوم نہیں ہوتا.ہاں یوں یہ معنے درست ہو سکتے ہیں کہ ان معنوں کو زمانہ نبوی سے مخصوص قرار دیا جائے اور
یہ کہا جائے کہ پہلے تو یہ سفر جائز تھے مگر اب تو مکہ والوں کو یہ سب کام چھوڑ کر صداقت محمدیت پرغور
کرنا چاہئے اور زیادہ سے زیادہ دین کی خدمت میں لگ جانا چاہئے.اگر یہ معنے کئے جائیں تو یقیناً
درست ہیں.چنانچہ دیکھ لو محمد رسول اللہ صل تعلیم کی بعثت کے بعد یہ سفر خود بخود بند ہو گئے کیونکہ
اللہ تعالیٰ نے حج کو اتنا مقبول کر دیا کہ مکہ والوں کو باہر جانے کی ضرورت ہی نہ رہی.وہیں بیٹھے
بٹھائے اللہ تعالیٰ ان کو رزق دے دیتا ہے.محمد رسول اللہ مال للعالم سے پہلے چونکہ مجتی کامل
نہیں ہوئی تھی اس لئے مکہ والوں کو ان سفروں کی ضرورت پیش آتی رہتی تھی.مگر
محمد رسول اللہ علیم کی بعثت کے بعد تجلی الہی کامل طور پر ظاہر ہو گئی اس لئے اب یہ ضرورت
نہیں تھی کہ مکہ والے سفر کریں.اگر ہم اس آیت کے یہ محدود معنے کرلیں تو پھر کوئی اعتراض
نہیں پڑتا.ہم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سفروں کو گلی برانہیں کہا بلکہ مکہ والوں کو اس امر کی
967
Page 976
طرف توجہ دلائی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی علیم کے ظہور کے بعد اب ان سفروں کی کوئی ضرورت
نہیں.تمہیں چاہئے کہ ان سفروں کو چھوڑ کر محمد رسول اللہ صل تعلیم کے زمانہ سے فائدہ اٹھاؤ اور
اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنا وقت گزارو.ان معنوں کے رُو سے یہ کفار پر ایک ضرب کاری اور
مسلمانوں کی عظیم الشان تعریف ہے.آخر مومن بھی تو مکہ کے ہی رہنے والے تھے اور ان کی
ضروریات بھی ویسی ہی تھیں لیکن وہ تو ایمان لاتے ہی سب کچھ چھوڑ کر تبلیغ حق اور خدمت دین
میں لگ گئے اور جب وہ ایسا کر سکتے تھے تو مکہ کے اور لوگ ایسا کیوں نہیں کر سکتے تھے.ان معنوں سے پھر احمدیوں کے لئے ایک سبق نکلتا ہے.انہیں سوچنا چاہئے کہ کیا مکہ
والوں پر خدا تعالیٰ کا کوئی زیادہ احسان تھا.جس طرح ان کو خدا تعالیٰ نے ناک کان اور منہ
دیئے تھے اسی طرح ہم کو اس نے ناک کان اور منہ بخشے ہیں.جس طرح اُن کو قویٰ عطا کئے
گئے تھے اسی طرح ہم کو قومی دیئے گئے ہیں.جو علوم اُن کو دیئے گئے تھے وہی علوم ہم کو دیے
گئے ہیں.جو قرآن اُن کو دیا گیا تھا وہی قرآن ہم کو دیا گیا ہے.اس میں سے کوئی حصہ کم تو
نہیں کر دیا گیا.اگر مکہ والوں کو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ تم اپنے سارے کام کاج چھوڑ کر
محمدرسول اللہ علیہ کی طرف توجہ کرو اور اپنے تمام اوقات خدمت دین میں صرف کرو تو یہ حکم
مکہ والوں کے ساتھ کوئی مخصوص تو نہیں تھا.جو حالت اُن
کی تھی وہی حالت ہماری ہے.اور جو
صداقت ان کے پاس تھی وہی صداقت ہمارے پاس ہے.جب ہماری جماعت دعوی کرتی
ہے کہ خدا تعالیٰ نے اپنی تمام صداقتوں کا احیاء حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعہ
فرمایا ہے تو سورۃ ایلاف میں جس صداقت کو پیش کیا گیا ہے لازماً ہمیں اس صداقت کا بھی
از سر نو احیاء کرنا پڑے گا.ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس سورۃ میں تو قریش مخاطب کئے گئے ہیں ہم ایسا کیوں کریں.اس
لئے کہ ہماری جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمانہ میں محمد رسول اللہ علی ایم کو
دوبارہ ظلی رنگ میں مبعوث فرمایا ہے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت در حقیقت
968
Page 977
محمد رسول اللہ علم کی ہی بعثت ثانیہ ہے.جب ہماری جماعت یہ تسلیم کرتی ہے کہ
حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام محمد رسول الله علیم کے حل کامل میں تو ہماری جماعت کو
یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ بیت اللہ کا ظل وہ مقام ہے جہاں خدا تعالیٰ کا نام روشن ہوتا ہے اور
صحابہ کا ظل وہ جماعت ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر ایمان لا چکی ہے.اس صورت
میں جو فرائض اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیت اللہ میں رہنے والوں پر عائد ہو چکے ہیں یقیناً وہی
فرائض ہماری جماعت پر بھی عائد ہوتے ہیں.دنیا میں بھی ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ جب باپ مر
جاتا ہے تو تمام بھائیوں میں سے بڑا بھائی اس کا قائم مقام بن جاتا ہے.اُس وقت کوئی
نہیں پوچھتا کہ ہمارا یہ بڑا بھائی باپ کا قائم مقام کس طرح بن گیا.کیونکہ عقل کہتی ہے کہ جب
اصل سامنے نہ ہو تو بہر حال اس کا کوئی ظل ہونا چاہئے.اور پھر عقل یہ بھی کہتی ہے کہ جو
ذمہ واریاں اصل پر عائد ہوتی ہیں وہی ذمہ داریاں ظل پر بھی عائد ہوں گی.پس ہماری جماعت جب ظلی رنگ میں محمد رسول اللہ مالی کی ہی جماعت ہے اور ظل محمد پر
ایمان لا کر ہم محمد رسول اللہ علیم کی جماعت میں شامل ہو چکے ہیں تو ہمیں بھی ان آیات کا اپنے
رض
آپ کو ویسا ہی مخاطب سمجھنا پڑے گا جیسے صحابہ مخاطب تھے.اور ہمیں بھی وہی کچھ کرنا پڑے گا جو
صحابہ نے کیا.اللہ تعالیٰ ان آیات میں زمانہ محمدی کے لوگوں سے کہتا ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا
البيت تم کو چاہئے کہ تم عبادتوں میں اپنا وقت لگاؤ اور ذکر الہی کی عادت ڈالو.یہی کام احمدیوں کا
ہے.مگر افسوس ہے کہ احمدیوں نے اب تک اس مقام کو نہیں پایا.کتنے احمدی ہیں جو اس معیار
پر پورے اترتے ہیں.بے شک دوسروں سے زیادہ چندہ دینے والے احمدی موجود ہیں مگر چندہ
سے تو دین نہیں پھیلتا.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ دین کی ترقی تو نفس
کی صفائی اور عبادت کی کثرت سے ہوتی ہے.مگر میں دیکھتا ہوں کہ ذکر الہی اور عبادت کی طرف
بہت ہی کم توجہ ہے.فرض نمازیں بیشک وہ دوسروں سے زیادہ ادا کرتے ہیں مگر ذکر الہی کرنا،
مساجد میں بیٹھنا، راتوں کو اٹھ کر تہجد ادا کرنا، اعتکاف کرنا.یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا
969
Page 978
قرآن کریم میں ذکر آتا ہے اور جو نفس کی اصلاح کے ساتھ نہایت گہرا تعلق رکھتی ہیں.مگر ہماری
جماعت کی توجہ ان کی طرف بہت کم ہے.حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعائیں کیں ان میں
بھی آتا ہے کہ الہی تیرے لئے اعتکاف کرنے والے لوگ اور تیری عبادت میں اپنا وقت
گزارنے والے لوگ میری اولاد میں ہمیشہ پیدا ہوتے رہیں.مگر میں دیکھتا ہوں کہ احمدیوں کی
اس طرف بہت کم توجہ ہے حالانکہ جب تک ان باتوں کی طرف توجہ نہ ہو انسان کا نفس کبھی جلا
نہیں پاتا.جلا نفس ہمیشہ ذکر الہی سے ہوتا ہے.نمازوں کے متعلق بھی میں دیکھتا ہوں کہ اس امر کی طرف کوئی توجہ نہیں کی جاتی کہ نمازیں
آہستگی کے ساتھ پڑھیں.لوگ سنتیں جلدی جلدی ختم کر کے مسجد سے بھاگنے کی کوشش
کرتے ہیں.جب فرض نماز ختم ہوتی ہے اور سنتیں پڑھنے کا وقت آتا ہے تو چھٹا پٹ ایک دوڑ
شروع ہو جاتی ہے جو نہایت نامناسب اور اسلامی تعلیم کے خلاف حرکت ہے.ہماری
جماعت کے دوستوں کا فرض ہے کہ وہ ٹھہر ٹھہر کر نمازیں پڑھا کریں اور اپنے اوقات کا ایک بڑا
حصہ ذکر الہی اور دعاؤں میں صرف کیا کریں اور دوسرے مسلمانوں سے بھی انہیں یہی کہنا
چاہئے کہ وہ عبادت اور ذکر الہی پر زور دیں، کیونکہ اسلام کی اصل ترقی ذکر الہی اور عبادت پر زور
دینے سے ہی ہوگی.آج کل کے لوگ مغربی تہذیب کے ماتحت یہ سمجھتے ہیں کہ ذکر الہی وغیرہ کرنا اور مصلے پر
بیٹھے رہنا وقت کو ضائع کرنا ہے.حالانکہ یہ مصلے پر بیٹھ کر ذکر الہی کرنے والے ہی تھے جنہوں
نے بارہ سال کے اندر اندر آدھی دنیا تہ و بالا کر دی.اس سے صاف پتہ لگتا ہے کہ مصلے پر بیٹھنے
سے وقت ضائع نہیں ہوتا بلکہ انسان کو ایسی برکت ملتی ہے کہ وہ بڑے بڑے کام تھوڑے سے
وقت میں کر لیتا ہے.پس مصلے پر بیٹھنے کے معنے نکما پن کے نہیں بلکہ درحقیقت اس سے ایسی
مہارت پیدا ہو جاتی ہے اور دل میں اس قسم کا نور پیدا ہو جاتا ہے کہ تھوڑے سے وقت میں
انسان بڑے بڑے کام کر لیتا ہے.اگر تین گھنٹے وہ ذکر الہی میں مصروف رہتا ہے تو بیشک
970
Page 979
بظاہر اس کے تین گھنٹے وقت میں سے کم ہو جائیں گے مگر انہی تین گھنٹوں کی بدولت وہ آٹھ
گھنٹوں میں وہ کچھ کام کر لے گا جو باقی 24 گھنٹوں میں بھی نہیں کرسکیں گے.پس عبادت کی
کثرت ، تہجد اور ذکر الہی کی طرف توجہ کرو اور اپنی زندگیاں دین کی خدمت کے لئے وقف
کرو.میں بتا چکا ہوں کہ ابھی ہماری جماعت میں بہت تھوڑے لوگ ہیں جنہوں نے خدمت
دین کے لئے اپنی زندگیاں وقف کی ہوں اور پھر جو اپنی زندگیاں وقف کر چکے ہیں ان میں سے
بھی ایک حصہ ایسا ہے جو اپنے فرائض کو نہیں سمجھتا...حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا نام خدا تعالیٰ نے
ابراہیم بھی رکھا ہے جس سے
خدا تعالیٰ کا یہی منشاء ہے کہ آپ کی اولاد اسماعیلی نمونہ کو اختیار کرے اور دین کے لئے اپنے
آپ کو وقف کر دے.اس کے بعد خدا انہیں زیادہ دے تو وہ زیادہ قبول کرلیں اور اگر کم دے تو
کم پر راضی رہیں.یہ خدا تعالیٰ کی مرضی پر منحصر ہے.حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے
بعض فاقہ زدہ نبی بھی ہوئے ہیں اور حضرت سلیمان جیسے بادشاہ بھی گزرے ہیں جن کے لشکروں
اور نوکروں کی تعداد ہی ہزاروں تک پہنچتی تھی.میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ جماعت کے سفلی طبع
لوگ یا منافق طبقہ ان کو تو ادنی نگاہ سے دیکھتا ہے جو دین کی خدمت کرتے ہیں اور ان کی
تعریف کرتا ہے جو دنیا کمانے میں لگے ہوئے ہیں.میں خوب سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کا ایک
حصہ جاہل ہے اور دوسرا منافق جو اس طرح جماعت کو تباہ کرنا چاہتا ہے.مگر میں جانتا ہوں کہ
خدا تعالیٰ کا فعل ایک دن ایسے سب لوگوں کو خس کم جہاں پاک کردے گا.کیونکہ مومنوں کا دور
ابھی آنا ہے.بہر حال میں جماعت کو یہ انتباہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس بارہ میں ہماری جماعت
خطر ناک کوتاہی کا ارتکاب کر رہی ہے.دین کی خدمت کے لئے جتنے لوگوں کو اپنی زندگی
وقف کرنی چاہئے اتنے لوگ اپنی زندگی وقف نہیں کر رہے اور پھر جو زندگی وقف کرتے ہیں وہ
بھی اپنے فرائض کو پورے طور پر ادا نہیں کر رہے.حالانکہ جب تک اس امر کی طرف توجہ
نہیں ہوگی ہمارا کبھی بھی وہ پیمان پورا نہیں ہو گا جو ہم خدا کے ساتھ بیعت کے وقت کرتے ہیں.971
Page 980
اور جب تک ہم اپنے پیمان کو پورا نہیں کرتے اس وقت تک خدا تعالیٰ کا ہمارے متعلق جو عہد
ہے اس کے بھی ہم کبھی حقدار نہیں ہو سکتے.اب میں پھر نفس مضمون کی طرف آتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ
نتیجہ ہے لا يُلفِ قريش الفِهِمُ رِحْلَةَ الشَّتَاءِ وَالصَّيْفِ کا.یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے
اہل مکہ سے احسان اور سلوک اسی لئے کیا تھا کہ وہ ہماری عبادت کرتے.آخر کیا حق تھا ان کا ہم پر
کہ ہم دوسروں کے مقابلہ میں ان سے نمایاں سلوک کرتے.کیا یورپ والے ہمارے دشمن تھے؟
کیا ہندوستان والے ہمارے دشمن تھے؟ کیا حبشی ہماری مخلوق نہیں تھے؟ پھر کیوں ہم نے ان کی
ترقی کا خاص سامان کیا؟ اس لئے کہ وہ ہمارے گھر کے پاس رہتے ہیں.تا ایسانہ ہو کہ انہیں روٹی کی
تکلیف ہو اور وہ اس مقام کو چھوڑ کر بھاگ جائیں.مگر دیکھو ہم تو انہیں روٹی دیتے رہے مگر انہوں
نے ہمارا خیال نہ رکھا حالانکہ انہیں چاہئے تھا کہ اس احسان کے بدلے میں وہ رَبُّ الْبَیت کی
عبادت کرتے اور ہمارے احسانات کی قدر کرتے.یہاں رَبُّ الْبَیت کیوں کہا ہے ؟ صرف بیت کیوں نہیں کہا.اس لئے کہ قرآن کریم
اس بات کا قائل نہیں کہ کوئی بے جان چیز اپنے اندر طاقتیں رکھتی ہے.وہ طاقتوں کا مالک
صرف خدا تعالیٰ کو سمجھتا ہے.پس توحید کامل کا سبق دینے کے لئے یہاں رَبُّ الْبَيْتِ کے
الفاظ رکھے گئے ہیں.یعنی مکہ والے یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس بیت کی وجہ سے انہیں یہ اعزاز
حاصل ہوا ہے.حالانکہ یہ اعزاز انہیں بیت کی وجہ سے نہیں بلکہ رَبُّ الْبَیت کی وجہ سے
حاصل ہوا ہے.گویا نتیجہ یہ نکالا گیا ہے کہ تم یہ مت سمجھو کہ خانہ کعبہ نے کچھ کیا ہے.خانہ کعبہ
کچھ نہیں کر سکتا.وہ مٹی کا ایک مکان ہے اور اس میں یہ طاقت ہر گز نہیں کہ وہ کسی کو کوئی فائدہ
پہنچا سکے.اس گھر کا رب ہے جو سب طاقتوں کا مالک ہے.احادیث میں آتا ہے حضرت عمر
رضی اللہ عنہ ایک دفعہ طواف کر رہے تھے کہ آپ حجر اسود کے پاس سے گزرے اور آپ نے
اسے اپنی سوٹی ٹھکرا کر کہا میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے اور تجھ میں کچھ بھی طاقت نہیں.مگر
972
Page 981
میں خدا کے حکم کے ماتحت تجھے چومتا ہوں.یہی جذ بہ توحید تھا جس نے ان کو دنیا میں سر بلند
کیا.وہ خدائے واحد کی توحید کے کامل عاشق تھے.وہ یہ برداشت ہی نہیں کر سکتے تھے کہ اس
کی طاقتوں میں کسی اور کو شریک کیا جائے.بے شک وہ حجر اسود کا ادب بھی کرتے تھے مگر
اس لئے کہ خدا تعالیٰ نے کہا ہے اس کا ادب کرو.نہ اس لئے کہ حجر اسود کے اندر کوئی خاص
بات ہے.وہ سمجھتے تھے کہ اگر خدا تعالیٰ ہمیں کسی حقیر سے حقیر چیز کو نچومنے کا حکم دے دے تو ہم
اس کو چومنے کے لئے بھی تیار ہیں کیونکہ ہم خدا تعالیٰ کے بندے ہیں، کسی پتھر یا مکان کے
بندے نہیں.پس وہ ادب بھی کرتے تھے اور تو حید کو بھی نظر انداز نہیں ہونے دیتے تھے اور یہی
ایک سچے مومن کا مقام ہے.ایک سچا مومن بیت اللہ کو ویسے ہی پتھروں کا ایک مکان سمجھتا
ہے جیسے دنیا میں اور ہزاروں مکان پتھروں کے بنے ہوئے ہیں.ایک سچا مومن حجر اسود کو
ویسا ہی پتھر سمجھتا ہے جیسے دنیا میں اور کروڑوں پتھر موجود ہیں مگر وہ بیت اللہ کا ادب بھی کرتا ہے،
وہ حجر اسود کو چومتا بھی ہے.کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرے رب نے ان چیزوں کے ادب کرنے
کا مجھے حکم دیا ہے.مگر باوجود اس کے کہ وہ اس مکان کا ادب کرتا ہے، باوجود اس کے کہ وہ حجر
اسود کو چومتا ہے، پھر بھی وہ اس یقین پر پوری مضبوطی کے ساتھ قائم ہوتا ہے کہ میں خدائے
واحد کا بندہ ہوں ، کسی پتھر کا نہیں.یہی حقیقت تھی جس کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اظہار
فرمایا.آپ نے حجر اسود کو سوئی ماری اور کہا میں تیری کوئی حیثیت نہیں سمجھتا.تو ویسا ہی پتھر
ہے جیسے اور کروڑوں پتھر دنیا میں نظر آتے ہیں.مگر میرے رب نے کہا ہے کہ تیرا ادب کیا
جائے اس لئے میں ادب کرتا ہوں.یہ کہہ کر وہ آگے بڑھے اور اس پتھر کو بوسہ دیا.اس کا
مطلب یہی تھا کہ خدا نے تیرا ادب سکھایا ہے اس لئے میں ادب کرتا ہوں ورنہ تیرے اندر ذاتی
طور پر کوئی ایسی طاقت نہیں جس کی بناء پر تجھے چوما جاسکے.جب اس احساس کے ساتھ ہم
حجر اسود کو چومتے ہیں کہ ہمارے خدا نے اس کو چومنے کا حکم دیا ہے ورنہ وہ ایک معمولی پتھر
ہے تو ہم تو حید پر قائم ہوتے ہیں.اور جب ہم اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور اس پتھر کو کسی
973
Page 982
خاص خوبی کا مالک سمجھ لیتے ہیں تو ہمارا یہی فعل مشرکانہ فعل بن جاتا ہے.حضرت عمرؓ نے
حجر اسود کو چوما مگر وہ مشرک نہیں تھے کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ حجر اسود اپنی ذات میں کوئی اہمیت
نہیں رکھتا.میرے رب
کا حکم مجھے لایا اور میں نے اسے چوما.لیکن اگر کوئی دوسرا شخص حجر اسود
کو چومتا ہے اور دل میں سمجھتا ہے کہ حجر اسود میں کوئی خاص بات ہے جس کی وجہ سے اسے چوما
جاتا ہے تو وہی شخص مشرک بن جائے گا.اگر ایک شخص خانہ کعبہ کا اس لئے طواف کرتا ہے کہ
میرے خدا نے اس کے طواف کرنے کا حکم دیا ہے تو وہ بڑا موحد ہے.اور اگر کوئی شخص خانہ
کعبہ کا اس لئے طواف کرتا ہے کہ اس گھر میں کوئی خاص طاقت ہے تو وہ مشرک ہے.یہی
مضمون اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا ہے کہ تم سمجھتے ہو اس بیت کی وجہ سے تمہیں یہ
اعزاز حاصل ہوا ہے.احمقو! یہ سب کچھ اس بیت نے نہیں کیا بلکہ رَبُّ الْبَيت نے کیا ہے.اس گھر کو تو خدا نے محض ایک علامت کے طور پر مقرر کیا ہے.جیسے پرانے زمانہ میں دستور تھا
کہ بادشاہ کسی بکرے یا اونٹ وغیرہ پر اپنا نشان لگا کر اسے آزاد چھوڑ دیتے تھے اور کسی کی
طاقت نہیں تھی کہ اس کو نقصان پہنچا سکے اور اگر کوئی اس کو نقصان پہنچاتا تو اس کے معنے یہ
ہوتے تھے کہ بادشاہ کی ہتک کی گئی ہے.چنانچہ جب کوئی مخالف بادشاہ اس بکرے یا اونٹ
کو مارڈالتا تو اس سے لڑائی شروع ہو جاتی تھی.اس لئے نہیں کہ اس نے اونٹ کو مارا ہے.اس لئے نہیں کہ اس نے گھوڑے کو مارا ہے.اس لئے نہیں کہ اس نے بکرے کو مارا ہے.اس لئے نہیں کہ اس نے دنبہ کو مارا ہے.بلکہ اس لئے کہ بادشاہ یہ سمجھتا تھا کہ اس نے میری
ہتک کی ہے.اسی طرح بیت اللہ کو خدا تعالیٰ نے محمد رسول اللہ علی ایم کی امت کے لئے ایک
مرکز اور اولاد ابراہیم کو جمع رکھنے کا ایک ذریعہ بنایا ہے.پس وہ خدا کی ایک علامت ہے جو دنیا
میں پائی جاتی ہے.اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ اس گھر میں کوئی خاص بڑائی پائی جاتی ہے تو وہ
مشرک ہے اور اگر کوئی شخص اس کی یہ سمجھ کر ہتک کرتا ہے کہ یہ خدا تعالیٰ کی مقرر کردہ نشانی
نہیں تو وہ خدا کا بھی دشمن ہے.ایک سے وہ معاملہ کیا جائے گا جو مشرکوں سے کیا گیا اور
974
Page 983
دوسرے سے وہ معاملہ کیا جائے گا جو اصحاب الفیل سے کیا گیا.صرف اسی شخص کا نقطۂ نگاہ صحیح
سمجھا جائے گا جو یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ کیا رب البيت نے کیا ہے.بیت نے نہیں کیا.اسی
کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ.جو کچھ ملہ
والوں سے سلوک ہو رہا ہے اس کی وجہ رَبُّ البیت کے سوا کوئی نہیں.اگر اس گھر کا کوئی
رب نہ تھا تو اصحاب الفیل کو کس نے تباہ کیا.اگر رب البيت نہ تھا تو مکہ کی حفاظت اس طرح
صدیوں تک کس نے کی.اگر رب البيت نہ تھا تو مکہ والوں کو رزق کس نے مہیا کیا.اگر
رَبُّ البيت نہ تھا تو ان کے ان سفروں میں یہ برکات کس طرح رکھی گئیں.اگر رب البيت نہ
تھا تو آنے والے موعود کی یاد دلانے کے لئے جس کی خاطر یہ گھر بنایا گیا تھا مگہ والوں کو ان
ملکوں سے کس نے روشناس کروایا.پس جب تمہارے ساتھ جو کچھ سلوک کر رہا ہے خدا تعالیٰ کر
رہا ہے تو یہ کیسی قابل شرم حرکت ہے کہ تم خدا کو چھوڑ کر لات اور منات اور علی کی پرستش کر
رہے ہو اور سمجھتے ہو کہ خانہ کعبہ سے تعلق رکھنے کی وجہ سے ہم جو جی چاہے کرلیں.ہمارے لئے
جائز ہے.تمہیں یاد رکھنا چاہئے کہ اس خانہ کعبہ کی عزت بھی رب البیت کی وجہ سے ہے اور
جب اس کی عزت بھی رب البیت سے وابستہ ہے اور اسی نے تم کو ترقیات بخشی ہیں تو کیا تمہارا
فرض نہیں کہ تم شرک چھوڑ دو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو.گویا عبادت اور توحید دونوں پر اس
آیت میں زور دیا گیا ہے.کہا جاسکتا ہے کہ جھوٹے معبودوں اور مندروں اور پجاریوں کی بھی تو دنیا میں عزت کی جاتی
ہے.پھر کیا وہ عزت بھی اس بات کا ثبوت ہوتی ہے کہ بتوں نے ان کو عزت دی ہے.یعنی تم
یہ کہتے ہو کہ اس خانہ کعبہ کی عزت رَبُّ البیت کی وجہ سے ہے حالانکہ دنیا میں ایسے مندر بھی
موجود ہیں جن کی بڑی عزت کی جاتی ہے پھر کیا ان کی عزت بھی ان کے بتوں کی طرف منسوب
ہوسکتی ہے اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان بتوں نے ان کو عزت دی ہے.اس کا جواب یہ ہے کہ جھوٹی اور سچی چیزیں ایک ہی وقت میں دنیا میں موجود رہتی ہیں.سونا
975
Page 984
بھی موجود ہوتا ہے اور ملمع بھی موجود ہوتا ہے مگر کیا ملمع کی وجہ سے لوگ سونے کو چھوڑ دیا کرتے
ہیں؟ اسی طرح دنیا میں سیپ کے بنے ہوئے موتی بھی موجود ہیں.اور اصلی موتی بھی موجود
ہیں.نقلی ہیرا بھی موجود ہے اور اصلی ہیرا بھی موجود ہے.ایسی صورت میں ہم کیا کرتے ہیں.کیا ہم اصلی چیزوں کو چھوڑ دیا کرتے ہیں یا ہم یہ کیا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسی امتیازی
علامات ہیں جن پر پر کھ کر ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ جھوٹا کونسا ہے اور سچا کونسا ہے.ہم جھوٹے
موتیوں کی وجہ سے اصلی موتیوں کو چھوڑ نہیں کرتے.ہم جھوٹے ہیروں کی وجہ سے اصلی
ہیروں کو چھوڑا نہیں کرتے.ہم جھوٹے سونے کی وجہ سے اصلی سونے کو چھوڑا نہیں کرتے.بلکہ ہم یہ کہا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسے امتیازی نشانات ہیں جن پر پر کھ کر ہم معلوم کر سکتے
ہیں
کہ نقلی چیز کونسی ہے اور اصلی چیز کونسی.اسی طرح اس معاملہ میں بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ
عزت جو خانہ کعبہ کو حاصل ہوئی خدا تعالیٰ کی طرف سے تھی یا نہیں اور اگر خدا تعالیٰ کی طرف
سے تھی تو اس کا امتیازی نشان کیا تھا جو اسے دوسرے معبدوں اور مندروں سے ممتاز کر دے.اسی کو ایک اور مثال سے یوں
سمجھ لو کہ ماں باپ بچے کو پالتے ہیں اور ماں باپ کی خدمت
بچہ سے طبعی محبت کا ثبوت ہوتی ہے لیکن بعض دفعہ ٹھگ بچہ چرا کر لے جاتے ہیں اور بچہ کو آئندہ
کی شرارت کی غرض سے پالتے ہیں.وہ اس کو بداخلاق، چور اور ڈاکو بنانے کی کوشش
کرتے ہیں مگر بہر حال وہ پالتے محبت سے ہیں.اگر ماں باپ کی طرح محبت سے نہ پالیں تو وہ
فوراً بھاگ جائے.گویا وہ محبت تو کرتے ہیں مگر ان کی محبت جھوٹی ہوتی ہے.اب کیا ان کا
پالنا اس امر کی دلیل کے طور پر پیش کیا جاسکتا ہے کہ ماں باپ کو بھی بچہ سے محبت نہیں ہوتی.حقیقت یہ ہے کہ جس طرح اصلی اور نقلی چیزوں میں بڑا بھاری فرق پایا جاتا ہے اسی طرح
جھوٹے معبودوں اور مندروں اور پجاریوں کی عزت اور اس عزت میں بڑا بھاری فرق ہے جو
خانہ کعبہ کو حاصل ہے.اور وہ فرق یہ ہے کہ خانہ کعبہ اتفاقی طور پر معزز نہیں ہوا بلکہ خانہ کعبہ
کی بنیاد اللہ تعالیٰ کے الہام سے رکھی گئی.چنانچہ قرآن کریم فرماتا ہے اولَ بَيْتٍ وُضِعَ
976
Page 985
للناس یہ سب سے پہلا گھر تھا جو سب دنیا کے فائدہ کے لئے بنایا گیا تھا.یہ ظاہر ہے کہ
پرانے زمانے کے قومی مذہب ایسا گھر نہیں بنا سکتے جو سب دنیا کے لئے ہو.ایسا گھر
خدا تعالی ہی کی طرف سے اور اسی کے الہام سے مقرر کیا جا سکتا ہے.اس کے بعد زمانہ
ابراہیمی میں پھر خدا تعالیٰ کے الہام کے مطابق اس کی عمارت کی تجدید ہوئی.چنانچہ قرآن کریم
فرماتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں خدا کے لئے اس گھر کو بناتا ہوں اور اس لئے
بنا تا ہوں کہ یہاں لوگ آئیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اس کے گھر کا طواف کریں، عبادت
اور ذکر الہی میں اپنا وقت بسر کریں اور آنے والوں کی خدمت کریں.پھر انہوں نے دعا کی کہ
خدایا تو بھی اس گھر کو امن دیجیئو اور اس کے رہنے والوں کو اپنے پاس سے رزق دیجیئو اور پھر
ان میں سے ایک نبی پیدا کیجیئو جو انہیں تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائے.انہیں کتاب اور
حکمت سکھائے.اور ان کے نفوس کا تزکیہ کرے.یہ دعا تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
خانہ کعبہ کی بنیا د ر کھتے وقت کی.اُس وقت کی جب خانہ کعبہ کی ترقی کے کوئی آثار نہ تھے.اس
وقت کی جب اس کی آبادی کے کوئی آثار نہ تھے.اُس وقت کی جب وہ محض ایک وادی
غیر ذی زرع تھے.اُس وقت کی جب اس میں پانی کا ایک گھونٹ اور گندم کا ایک دانہ بھی
موجود نہیں تھا.پس اس کے بعد خانہ کعبہ کی جو کچھ ترقی ہوئی اسے یقیناً ہم اس دعا اور پیشگوئی
کی طرف منسوب کریں گے اور کہیں گے کہ یہ سلوک محض اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا.اس کے
مقابلہ میں دنیا میں بیشک لاکھوں مندر موجود ہیں مگر کیا ان میں سے کوئی ایک مندر بھی ایسا ہے
جس کی ترقی کسی پیشگوئی کے ماتحت ہوئی ہو؟ یا کیا ان مندروں میں سے کوئی ایک مندر بھی ایسا
ہے جس کو مانے والے آج ہی اس قسم کی پیشگوئی دنیا میں شائع کرسکیں ؟ اگر ان میں ہمت اور
طاقت ہے تو وہ ایسی پیشگوئی کریں اور پھر دیکھیں کہ اس کا کیا نتیجہ ہوتا ہے.یوں کسی مندر کی عزت ہونا اور بات ہے اور پیشگوئی کے ماتحت عزت ہونا اور بات ہے.اگر ایک شخص کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے قبل از وقت کہہ دیتا ہے کہ ابھی زید آئے گا اور پھر
977
Page 986
واقعہ میں زید آجاتا ہے تو وہ کہ سکتا ہے کہ دیکھو میری بات پوری ہوگئی.لیکن ایک اور شخص جو
چپ کر کے بیٹھا رہتا ہے اگر وہ کہے کہ دیکھو میری بات پوری ہوگئی زید آ گیا ہے تو ہر شخص اس
پر بنے گا کہ تم نے یہ بات ہی کب کی تھی کہ زید کے آنے پر تم کہہ رہے ہو کہ میری بات پوری
ہو گئی ہے.اسی طرح خانہ کعبہ کی بنیا در کھتے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک پیشگوئی
کی.اس میں یہ بھی ذکر تھا کہ خانہ کعبہ ترقی کرے گا.یہ بھی ذکر تھا کہ لوگ یہاں حج اور طواف
کے لئے آئیں گے.یہ بھی ذکر تھا کہ لوگ یہاں بسیں گے.یہ بھی ذکر تھا کہ اس گھر کو محفوظ
رکھا جائے گا اور کوئی دشمن اسے تباہ نہیں کر سکے گا.یہ بھی ذکر تھا کہ اس مقام پر رہنے والوں کو
اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق دیا جائے گا.جب ایک ایک کر کے تمام پیشگوئیاں پوری ہوگئیں
اور پھر مخالف حالات میں پوری ہوئیں تو یقیناً ان پیشگوئیوں کا پورا ہونا اپنی ذات میں اس بات کا
ثبوت ہے کہ خانہ کعبہ سے جو کچھ سلوک ہوا وہ اتفاقی نہیں تھا بلکہ محض اللہ تعالیٰ کی طرف سے
تھا.لیکن دوسرے مندروں میں سے اگر کسی کو کوئی عزت حاصل ہوئی ہے تو چونکہ اس کے
ساتھ کوئی پیشگوئی نہیں تھی اس لئے اسے محض اتفاق پر محمول کیا جائے گا.پھر خانہ کعبہ کا
محل وقوع دیکھ لو.حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ایسی جگہ یہ گھر بنایا جہاں کوئی آبادی
نہیں تھی.حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ایسی جگہ یہ گھر بنایا جس کے ارد گرد بھی
میلوں میل تک کوئی آبادی نہیں تھی.حضرت ابراہیم السلام نے ایک ایسی جگہ یہ گھر بنایا
جہاں پانی موجود نہیں تھا.حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ایسی جگہ یہ گھر بنایا جہاں کھیتی
موجود نہیں تھی.گویا خدائی ہاتھ کا ثبوت دینے کے لئے جو جگہ ہر قسم کی ترقی کے سامانوں سے
محروم تھی وہی جگہ اس گھر کے لئے تجویز کی گئی.پانی آبادی کے لئے ضروری ہوتا ہے مگر
وہاں پانی نہیں تھا.کھیتی آبادی کے لئے ضروری ہوتی ہے مگر وہاں کھیتی نہیں تھی.شہر اور ارد گرد
کی آبادی آبادی کے لئے ضروری ہوتی ہے مگر وہاں نہ کوئی شہر تھا اور نہ اس کے ارد گرد کوئی
آبادی تھی.ان حالات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر دنیا میں یہ اعلان
978
Page 987
کرنا کہ یہاں لوگ آئیں گے اور حج بیت اللہ کریں گے اور پھر لوگوں کا وہاں آنا اور حج بیت اللہ
کرنا اور ایک غیر آباد مقام کا آباد ہو کر ایک بہت بڑا شہر بن جانا بتاتا ہے کہ جو کچھ ہوا
رب البیت کی طرف سے ہوا.اس کے مقابلہ میں اتفاقی طور پر اگر کسی مندر کو شہرت حاصل ہو
جاتی ہے تو وہ ہر گز اس مندر کے کسی بت کی طرف منسوب نہیں ہوسکتی.کیونکہ کب اس مندر کی
عظمت کے متعلق پیشگوئی کی گئی تھی.کب یہ کہا گیا تھا کہ اس کی لوگوں میں شہرت ہو جائے
گی اور کب کسی قوم اور مذہب نے اس دعوی کی سچائی پر اپنی عزت اور اپنی سچائی کی بازی
لگائی تھی.پس اسے اگر شہرت حاصل ہوئی ہے تو محض اتفاقی طور پر.جیسے لنڈن ایک بہت
بڑا شہر بن گیا.مگر اس کے لئے کوئی پیشگوئی نہیں تھی.نیو یارک ایک بہت بڑا شہر بن گیا مگر
اس کے لئے کوئی پیشگوئی نہیں تھی.بے شک وہ بہت بڑے شہر ہیں مگر ان کی ترقی اللہ تعالیٰ کی
طرف منسوب نہیں ہوسکتی.لیکن اگر لنڈن سے پچاسویں حصہ کے برابر بھی کوئی شہر اللہ تعالیٰ کی
پیشگوئی کے مطابق آباد ہوتا ہے تو ہم اسے اللہ تعالیٰ کا نشان قرار دیں گے.پس کسی مندر کی
مقبولیت اور خانہ کعبہ کی مقبولیت میں بڑا بھاری فرق ہے.خانہ کعبہ کی مقبولیت خدائی
پیشگوئیوں کے مطابق ہوتی ہے لیکن مندروں کی مقبولیت محض ایک اتفاقی امر ہے.جس طرح
سونے کے مقابلہ میں ملمع ہوتا ہے اسی طرح خانہ کعبہ کی عظمت کے مقابلہ میں کسی مندر کی عظمت
یا اس کی ترقی بھی ایک ملمع سے زیادہ اور کوئی حیثیت نہیں رکھتی.فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَأَمَنَهُمْ
مِّنْ خَوْفٍ
اس آیت نے اس مضمون کو بالکل واضح کر دیا ہے جس پر میں شروع سے زور دیتا چلا
آرہا ہوں.میں نے بتایا تھا کہ یہاں اصل ذکر خدا کی خدائی اور اس کی طاقت وقوت اور اس
کے فضل اور احسان کا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ وہ خدا ہی ہے جس نے رِحْلةَ الشَّتَاءِ
والصيف کی محبت پیدا کی اور وہ خدا ہی ہے جس نے انہیں سفر کی سہولتیں مہیا کر کے عزت
979
Page 988
اور شہرت دی.اب اس آیت میں اوپر کے اسی مضمون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا
ہے کہ جب قریش پر ہم نے اس قدر احسانات کئے ہیں تو کیا ان کا فرض نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی
عبادت کریں.اس خدا کی عبادت الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَأَمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ جس خدا
نے انہیں بھوک پر کھانا کھلایا اور ان کے خوف کو امن سے بدل دیا.* عربی زبان میں یہ قاعدہ ہے کہ کبھی اشارہ قریب کا ذکر پہلے آجاتا ہے اور اشارۃ بعید کا
ذکر بعد میں آتا ہے، اور کبھی ترتیب کلام کو مدنظر رکھا جاتا اور اسی کے مطابق اشارہ لایا جاتا
ہے.یہ دونوں طریق عربی زبان میں مروج ہیں اور دونوں طرح ضمائر کا استعمال ہوتا ہے.اس
جگہ اشارہ قریب کا ذکر پہلے کیا گیا ہے اور اشارہ بعید کا ذکر بعد میں کیا گیا ہے.اشارہ قریب
لا يُلفِ قُرَيْش الفِهِمْ رِحْلَةَ الشَّتَاءِ وَالصَّيْفِ تھا اور اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ قریش
بھوکے مرتے تھے ہم نے انہیں روٹی کھلائی.پس چونکہ روٹی کا قریب میں ذکر آتا تھا اس
لئے اللہ تعالیٰ نے پہلے روٹی کا ہی ذکر کیا اور فرمایا الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوع.اس کے بعد
دوسرا اشارہ جو اشارۃ بعید ہے سورۃ الفیل کی آخری آیت فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مأْكُولٍ کی طرف تھا
جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ابرہہ اور اس کے لشکر کو بھوسہ کی طرح اڑا دیا.اگر
ابرہہ کے لشکر کا گلی استیصال نہ کیا جاتا تو یمن سے مکہ کو مستقل خطرہ رہتا اور یمن کا سفر مکہ والوں
کے لئے بالکل ناممکن ہو جاتا.اسی طرح یمن سے لڑائی کی وجہ سے شام کا سفر بھی ناممکن ہو جاتا
کیونکہ یمن بھی روم کا صوبہ تھا.پس چونکہ اس صورت میں مکہ والوں کے لئے یہ دونوں سفر ناممکن
ہو جاتے.اس لئے اللہ تعالیٰ نے ایسا پُر ہیبت نشان دکھایا کہ یمن کی مسیحی حکومت بالکل تباہ ہو
گئی اور شام پر بھی رعب طاری ہو گیا اور مکہ والوں کے دونوں سفر قائم رہے.پس چونکہ یہاں
اشارة بعيد فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مأکول کی طرف تھا اور اللہ تعالیٰ اپنے اس احسان
کا ذکر کرنا چاہتا
تھا جو اس نے اصحاب الفیل کو تباہ کر کے مکہ والوں پر کیا اس لئے امنهُم مِّنْ خَوْفٍ کا ذکر اس
نے أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوع کے بعد کیا.980
Page 989
م اس آیت نے سورۃ الفیل کی آخری آیت کی طرف اشارہ کر کے ہمیں یہ بھی بتا دیا ہے کہ
لا يُلفِ قُريش الفِهِمْ رِحْلَةَ الشَّتَاءِ وَالصَّيْفِ کے جو مختلف معانی کئے گئے ہیں وہ سب
کے سب درست ہیں.یعنی اس سورۃ میں ایک مستقل مضمون بھی بیان کیا گیا ہے اور اس میں
پہلی سورۃ کے مضمون کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ نے سورة
ایلاف کے مستقل مضمون کی طرف اشارہ کر دیا اور امتهُم مِّن خَوْفٍ نے سورۃ الفیل کی طرف
اشارہ کر دیا.گویا یہ بھی درست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب الفیل کو ایلاف قریش کی غرض سے
تباہ کیا.اور یہ بھی درست ہے کہ ان کے دلوں میں رحلةَ الشَّتَاءِ وَالصَّيْفِ کے متعلق رغبت
پیدا کی تا کہ ان کو روٹی مل جائے اور مکہ میں اطمینان کے ساتھ بیٹھے رہیں.بہر حال اللہ تعالیٰ
اپنے ان دونوں انعامات کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ تم اس خدا کی عبادت کرو جس نے
تمہیں بھوک کی حالت میں کھانا کھلایا.جو تمہارے قافلوں کو شام اور یمن کی طرف لے گیا اور
اس طرح اس نے تمہارے لئے روٹی کا سامان کیا.اسی طرح تم اس خدا کی عبادت کرو جس
نے تمہارے خوف کو امن سے بدل دیا.یعنی اصحاب الفیل جب حملہ کر کے آئے تو اللہ تعالیٰ
نے انہیں تباہ کیا اور تمہارے لئے اس نے امن کی صورت پیدا کی.من جوع میں مین کا لفظ کیوں رکھا گیا ہے اور جوع پر تنوین کیوں آئی ہے؟ اس کی دو
وجوہ ہو سکتی ہیں اور دونوں ہی اس جگہ چسپاں ہوتی ہیں.پہلی یہ کہ تنوین تعظیم کے لئے آتی ہے.اگر اس امر کو مدنظر رکھا جائے تو الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوع کے یہ معنی ہوں گے کہ اے اہل مکہ
ہم نے تم کو ایک ایسی خطرناک بھوک سے بچایا ہے جس سے تمہارے بچنے کی کوئی صورت
نہیں تھی.واقعہ یہ ہے کہ وہ لوگ ایک وادی غیر ذی زرع میں پڑے ہوئے تھے.ایسے
غیر آبادخطہ میں رہتے ہوئے وہ بھوک کی موت سے کہاں بچ سکتے تھے.طائف میں بے شک
باغات وغیرہ تھے اور وہاں کسی قدر زراعت بھی ہوتی تھی مگر یہ زراعت بہت ناکافی تھی.مکہ کے
صرف چند امراء خاندان ہی ایسے تھے جن کو طائف سے غلہ آتا تھا.باقی لوگوں کے لئے یا تو
981
Page 990
یمین سے غلہ آتا تھا یا مدینہ اور اس کے نواحی علاقہ سے آتا تھا بلکہ بعض دفعہ شام سے بھی لانا
پڑتا تھا.زیادہ تر یمن سے ہی مگہ میں غلہ آتا تھا.اسی طرح کبھی کبھار حبشہ سے بھی آجاتا تھا.پس أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوع میں اللہ تعالیٰ اس امر کی طرف اشارہ فرماتا ہے کہ تمہارا جائے وقوع
ایسا تھا کہ تمہیں معمولی روٹی بھی کھانے کے لئے میسر نہیں آسکتی تھی مگر ہم نے محض اپنے فضل
سے ایسے حالات پیدا کر دیئے کہ تمہیں بافراغت کھانا میسر آ گیا اور تم بھوک کی تکلیف سے بچ
گئے.یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں من الجوع نہیں فرمایا.اگر من الجوع ہوتا تو اس
کے معنے محض بھوک کے ہوتے مگر من جوع کے یہ معنے ہیں کہ ایسی شدید بھوک جس سے
بچنے کی کوئی صورت نہیں تھی.اسی طرح اللہ تعالیٰ نے امنَهُمْ مِّنَ الْخَوفِ نہیں فرمایا بلکہ
امَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ فرمایا ہے.اس میں بھی اسی طرف اشارہ ہے کہ ہم نے صرف خوف دور
نہیں کیا بلکہ ایسا شدید خوف دور کیا جس نے تمہاری بنیادوں کو ہلا دیا تھا.غرض تنوین چونکہ تعظیم کے لئے آتی ہے اس لئے من جوع کے یہ معنے ہوں گے کہ ایسی
بھوک جس سے بچنے کی کوئی صورت نہیں تھی.اور من خوف کے یہ معنے ہوں گے کہ ایسا
خطر ناک خوف جس سے بچنے کی کوئی صورت نہیں تھی.چنانچہ اصحاب الفیل کے واقعہ میں
میں تفصیل کے ساتھ بیان کر چکا ہوں کہ حضرت عبد المطلب نے ابرہہ سے صاف طور پر کہہ دیا
تھا کہ ہم میں تم سے لڑنے کی کوئی طاقت نہیں.اگر یہ خدا کا گھر ہے تو وہ آپ اس کو بچاتا
پھرے.پھر ہذیل اور بنو کنانہ نے بھی متفقہ طور پر غور کرنے کے بعد اہل مکہ کو یہی مشورہ دیا
تھا کہ ہم تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے تم ابر ہ اور اس کے لشکر کے سامنے ہتھیار ڈال دوتا کہ وہ
جو چاہے کرلے.یہ کتنا بڑا خوف ہے کہ ایک قوم کی قوم ہتھیار ڈالنے کے لئے تیار ہوگئی.یہی
حکمت ہے جس کی بناء پر اللہ تعالیٰ نے یہاں من الخوف نہیں بلکہ مِنْ خَوْفٍ فرمایا ہے.یعنی
میں نے ایک عظیم الشان خوف سے تم کو بچایا.لیکن جہاں
تنوین تعظیم کے لئے آتی ہے وہاں عربی زبان میں تنوین تحقیر کے لئے بھی
982
Page 991
استعمال ہوتی ہے.اگر اس استعمال کو مدنظر رکھا جائے تو پھر من جوع کے یہ معنے ہوں گے کہ
ادنیٰ سے ادنی بھوک اور من خوف کے یہ معنے ہوں گے کہ ادنیٰ سے ادنی خوف.یعنی ہم نے
اتنی فراوانی اور کثرت کے ساتھ رزق دیا کہ مکہ والے چھوٹی سے چھوٹی بھوک سے بھی نجات پا
گئے.یہ خدا تعالیٰ کا کتنا بڑا فضل اور کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے مکہ والوں کو ایک ایسی
خطر ناک جگہ رکھ کر جہاں روٹی کا کوئی سامان نہ تھا ہر فرد کے لئے روٹی مہیا کر دی.حقیقتا اگر
غور کیا جائے تو یہ بڑے بھاری انعام اور فضل کا ثبوت ہے کہ ایسے خطرناک مقام پر رکھ کر اس
نے ہر ایک کو روٹی مہیا کی.ہر ایک کو با فراغت رزق دیا.یہاں تک کہ وہ ادنیٰ سے ادنی
بھوک کی تکلیف سے بھی محفوظ ہو گئے.اسی طرح امتهُمْ مِّنْ خَوْفٍ کے یہ معنے ہوں گے کہ
اللہ تعالیٰ نے مکہ والوں کو ادنیٰ سے ادنی خوف سے بھی نجات دی.یعنی ابر ہہ اور اس کے لشکر کو
اس نے حرم کی حدود میں داخل ہی نہیں ہونے دیا.باہر ہی اس کا خاتمہ کر دیا.اگر وہ مکہ میں
داخل ہو جاتا اور منجنیقوں سے پتھر برسانے لگتا تو کچھ نہ کچھ خوف اہلِ مکہ کو ضرور ہوتا جیسے
رسول کریم عالم کے بعد جب حجاج بن یوسف نے مکہ پر حملہ کیا تو روایات میں آتا ہے کہ
ایک منجنیق کا پتھر خانہ کعبہ کو بھی آلگا اور اس کا کچھ حصہ جل بھی گیا.بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ الم ترَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْبِ الْفِيْلِ میں جس
واقعہ کا ذکر کیا گیا ہے اگر وہ اسی طرح ہوا تھا تو حجاج نے جب حملہ کیا اس وقت خانہ کعبہ کا کچھ
حصہ کیوں جل گیا تھا اور کیوں اس کو پتھر بھی آلگا؟ اس کا جواب بعض لوگوں نے یہ دیا ہے کہ
اس کی نیت خانہ کعبہ کو پتھر مارنے کی نہیں تھی اتفاقی طور پر وہ اسے آلگا تھا.دوسرے آگ
فوراً بجھا دی گئی تھی اس سے کوئی نقصان نہیں ہوا تھا.بہر حال جیسا کہ میں بتا چکا ہوں
اصحاب الفیل کی تباہی رسول کریم یا لینے کے لئے بطور ار باص تھی اور خانہ کعبہ کی حفاظت اپنی
ذات میں اتنی مقصود نہیں تھی جتنی رسول کریم عالم کی حفاظت مقصود تھی.یہی وجہ ہے کہ جس
شان سے اس وقت نشان ظاہر ہوا اس شان کا نشان بعد میں ظاہر نہیں ہوا.بہر حال
983
Page 992
اللہ تعالیٰ نے اس وقت اہل مکہ کو ادنیٰ سے ادنی خوف سے بھی بچایا اور ابرہہ کو وہیں مار دیا.بعضوں نے کہا ہے کہ آمَنَهُم مِّنْ خَوْفِ میں اس قحط کی طرف اشارہ ہے جو
رسول کریم علیم کے زمانہ میں پڑا.احادیث میں آتا ہے کہ جب قریش مکہ نے رسول کریم
عالم کو بہت تنگ کیا اور سخت تکالیف پہنچائیں تو آپ نے دعا فرمائی کہ اللهُم خُذْهُمُ
بِسَنِينَ كَسَنِى يُوسُفَ یعنی اے اللہ تو ان لوگوں کو ویسے ہی پکڑ جیسے یوسف کے زمانہ میں تو
نے لوگوں کو قحط سے پکڑا تھا.اس پر مکہ میں ایک شدید قحط پڑا.آخر وہی لوگ جو رسول کریم
علیم کے شدید مخالف تھے انہوں نے آپ سے دعا کی درخواست کی.چنانچہ آپ نے دعا کی
جس پر کچھ اردگرد کے علاقہ میں بارشیں ہو گئیں.کچھ حبشہ کی حکومت نے وہاں غلہ بھجوا دیا اور
اس طرح قحط دُور ہوا.پس بعض لوگ کہتے ہیں کہ امنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ میں اسی قحط کی طرف اشارہ
ہے.مگر یہ درست نہیں.اس لئے کہ واقعات سے یہ ثابت ہے کہ یہ سورۃ نہایت ابتدائی
سورتوں میں سے ہے اور وہ قحط جو مکہ میں پڑا وہ شعب ابی طالب میں محصور ہونے کے وقت
پڑا.پس یہ آیت جب پہلے نازل ہو چکی تھی تو قحط کا اس کے ساتھ تعلق کیا ہوا.یہاں تو
اللہ تعالیٰ ان پر حجت کرتا ہے کہ اس نے ان کے خوف کو امن سے بدل دیا.جو چیز بھی ظاہر ہی
نہیں ہوئی تھی وہ ان کے لئے حجت کس طرح ہو سکتی تھی.بہر حال اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشگوئی کی
طرف اشارہ ہے خالی سفروں کی طرف اشارہ نہیں.چنانچہ جب ہم قرآن کریم کو دیکھتے ہیں تو
معلوم ہوتا ہے کہ حضرت
ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی تھی تو اس وقت آپ
نے ایک دعا فرمائی تھی جس کا اللہ تعالیٰ ان الفاظ میں ذکر فرماتا ہے.وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَيَنِيَّ أَنْ نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ -
اسی طرح آپ نے یہ دعا کی تھی کہ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ
بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِى إِلَيْهِمُ وَارْزُقْهُمْ
984
Page 993
مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ (ابراهيم (38) حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ
اے خدا تو اس گھر کو امن والا بنا ئیو اور مجھے اور میری اولاد کو شرک سے بچائیو.پھر کہتے ہیں
اے خدا میں نے اپنی اولاد کو تیرے مکرم و محترم گھر کے پاس ایک ایسی جگہ لا کر بسا دیا ہے
جہاں کوئی کھیتی باڑی نہیں ہوتی محض اس لئے کہ وہ نمازوں کو قائم کریں اور تیرے ذکر
میں مشغول رہیں فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِی إِلَيْهِمُ پس اے خدا تو خود لوگوں کے
دلوں میں تحریک کر کہ وہ ان کی طرف جھکیں وَارزُقُهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ اور
انہیں کھانے کے لئے ہر قسم کے پھل عنایت فرما تا کہ یہ تیرا شکر ادا کرتے رہیں.اس دعا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنی اولاد کے لئے دو باتیں مانگی
ہیں.امن اور رزق.اور پھر ذریعہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ امن اور رزق انہیں کس طرح ملے؟ آپ
فرماتے ہیں یہ دونوں چیزیں انہیں حکومت اور تلوار کے زور سے نہ ملیں.بیشک دنیا میں
حکومت کے زور سے امن بھی قائم ہو جاتا ہے اور حکومت لوگوں
کا روپیہ بھی کھینچ کھینچ کر لے آتی
ہے.مگر آپ فرماتے ہیں میں یہ پسند نہیں کرتا کہ انہیں اس رنگ میں یہ چیزیں ملیں.میری دعا
اور التجا یہ ہے کہ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِى إِلیہم لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت
پیدا ہوا اور وہ عقیدت کے ساتھ ان کی طرف جھکیں.گویا جو کچھ ملے زور اور طاقت سے نہ ملے بلکہ
عقیدت اور محبت کی وجہ سے ملے.یہ
کتنی کڑی شرطیں ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی
دعا میں لگادی ہیں.یہ ایسی ہی بات ہے جیسے کوئی شخص جنگل میں جا کر یہ دعا کرے کہ خدایا مجھے
پر بارش برسا.وہ میرے ارد گرد نہ برسے.وہ صرف آدھ گھنٹہ بر سے اور جب برس چکے تو فوراً
اسی جگہ سے ایک درخت نکل آئے.حضرت
ابراہیم علیہ السلام بھی اپنی اولاد کو ایک جنگل میں لا
کر بٹھا دیتے ہیں اور پھر دعا یہ کرتے ہیں کہ انہیں امن حاصل ہو.بھلا جنگل میں امن کہاں!
جنگل میں تو یہی ہو سکتا ہے کہ کوئی بھیڑیا آئے اور چیر پھاڑ جائے یا کوئی ڈاکو آئے اور وہ
لوٹ لے.پھر وادی غیر ذی زرع کہاں اور رزق کہاں ! مگر وہ ایک جنگل میں اپنی اولاد کو بٹھا
985
Page 994
کر یہ دعا کرتے ہیں کہ خدایا انہیں رزق عطا فرما.گویا اللہ تعالیٰ سے وہ اپنی اولاد کے لئے دو
چیزیں مانگتے ہیں.رزق بھی مانگتے ہیں اور امن بھی مانگتے ہیں اور مانگتے بھی وادئی غیر ذی زرع
میں ہیں.مگر پھر یہیں پر بس نہیں کرتے بلکہ ایک اور شرط یہ عائد کرتے ہیں کہ انہیں رزق اور
امن تو ملے مگر تلوار سے نہیں.حکومت اور طاقت کے زور سے نہیں بلکہ اس طرح کہ ان کی محبت
لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو اور وہ خود بخود عقیدتمندانہ جذبات کے ساتھ ان کی طرف جھکتے چلے
جائیں.یہ کتنی سخت اور کڑی شرائط ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعا کے ساتھ لگائی
ہیں.اس کے مقابلہ میں وہ دو باتیں اپنی اولاد کی طرف سے بھی کہتے ہیں.ایک یہ کہ وہ مکہ میں
رہیں گے اور دوسری یہ کہ خدا تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہیں گے اور وہ عبادت تو حید والی ہوگی.اللہ تعالیٰ اسی دعائے ابراہیمی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ
جُوعِ وَأَمَنَهُمْ مِّنْ خَوف.اے مکہ والو! ہم نے وہ وعدہ پورا کر دیا جو ہم نے ابراہیم کے ساتھ
کیا تھا.اب کیا تمہارا فرض نہیں کہ تم بھی اس عہد کو پورا کرو جو تمہاری طرف سے تمہارے
دادا ابراہیم نے کیا تھا.یہ دو باتیں کہ وہ مکہ میں رہیں گے اور عبادت خدا میں لگے رہیں گے اور
عبادت بھی تو حید والی کریں گے ہم نے نہیں کہی تھیں.ہم نے ابراہیم سے یہ نہیں کہا تھا کہ
اے ابراہیم چونکہ تو ہم سے دو چیزیں مانگ رہا ہے ہم بھی تجھ سے وہ چیزیں مانگتے ہیں.ہم
نے ابراہیم سے کوئی سودا نہیں کیا.بلکہ ابراہیم نے خود کہا کہ اے میرے رب میں تجھ سے یہ
سودا کرتا ہوں اور یہ سودا پیش کرنے والا تمہارا اپنا دادا تھا.اس کی بات کی پیچ تو تمہیں زیادہ
زیادہ ہونی چاہئے.ہم پر ابراہیم نے جو ذمہ داری رکھی تھی وہ ہم نے پوری کر دی.الذی
أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَأَمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ.اس نے جہاں کہا تھا ہم نے رزق پہنچایا.اس
نے کہا تھا کہ میری اولاد کو وادی غیر ذی زرع میں رزق دیا جائے.سوہم نے وادی غیر ذی
زرع میں ہی تمہیں رزق دے دیا.اس نے کہا تھا کہ انہیں اس خطرناک مقام پر امن دیا
جائے.سو ہم نے اس خطر ناک مقام پر تمہیں امن دے دیا.اس نے کہا تھا کہ یہ رزق اور
986
Page 995
امن انہیں تلوار کے زور سے نہ ملے بلکہ لوگوں کی محبت اور پیار کے نتیجہ میں ملے سو ہم نے لوگوں
کے دلوں میں تمہاری محبت قائم کر دی اور اب اسی محبت کے نتیجہ میں تمہیں رزق اور امن حاصل
ہو رہا ہے.اب کیا تمہارا فرض نہیں کہ تمہارے دادا نے تمہاری طرف سے جو وعدہ کیا تھا کہ
یہ اس گھر میں ہمیشہ کے لئے بس جائیں گے اور اس میں خالص تیری عبادت کو قائم کریں گے،
تم اسے پورا کرو.ہم نے کتنے عرصہ تک اپنے وعدہ کو پورا کیا.اس کے مقابلہ میں تمہاری
طرف سے بھی یہ وعدہ تھا کہ ہم مکہ میں رہیں گے اور خدائے واحد کی پرستش بجالائیں گے تم
ہزاروں سال سے شرک کرتے چلے آرہے ہو مگر ہم نے تمہیں کچھ نہیں کہا.کیونکہ تم کہہ سکتے
تھے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی تعلیم نہیں پہنچی.لیکن اب
تو محمدرسول اللہ ہم تمہاری
طرف بھیج دیئے گئے ہیں اور وہ تمہیں خدائے واحد کی طرف بلا رہے ہیں.مگر اے ظالمو! تم
اب بھی خدائے واحد کی طرف نہیں آرہے.987
(ماخوذ از تفسیر کبیر زیر سورة القريش)
Page 997
(XXXXXXXXX
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
قُلْ يَايُّهَا الْكَفِرُونَ
لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ
وَلَا انْتُمْ عُبِدُونَ مَا أَعْبُدُ
وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ
وَلَا انْتُمْ عَبدُونَ مَا أَعْبُدُن
لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِى دِينِ 6
سورة الكافرون
1 - (میں) اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا
( اور ) بار بار رحم کرنے والا ہے (پڑھتا ہوں)
2 ہم ہر زمانہ کے مسلمان سے کہتے ہیں کہ ) تو
اپنے زمانہ کے کفار سے ) کہتا چلا جا ( کہ ) سنو !
اے کا فرو!
3.میں تمہارے طریق کے مطابق عبادت نہیں کرتا.4.اور نہ تم میرے طریق کے مطابق عبادت کرتے ہو.5.اور نہ میں ( ان کی ) عبادت کرتا ہوں جن کی تم
عبادت کرتے چلے آئے ہو.6.اور نہ تم ( اس کی ) عبادت کرتے ہو جس کی
میں عبادت کر رہا ہوں.7.اوپر کا اعلان نتیجہ ہے اس کا کہ) تمہارا دین
تمہارے لئے ( ایک طریق کار مقرر کرتا ) ہے اور میرا
دین میرے لئے ( دوسرا طریق کار مقرر کرتا) ہے.989
Page 998
حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:
سورۃ کافرون مگی ہے.طبرانی اور ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس
رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ قریش نے ایک دفعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ہم
آپ کو اتنا مال دیتے ہیں کہ آپ مکہ میں سب سے بڑے دولتمند ہو جائیں.اور جس عورت کو
آپ پسند کریں اس کے ساتھ آپ کا نکاح کر دیتے ہیں.یہ سب کچھ آپ لے لیں اور ہمارے
معبودوں کی برائی بیان کرنے سے رُک جائیں اور ان کو بدی کے ساتھ یاد نہ کریں.اور اگر
آپ
کو یہ بات منظور نہیں تو ہم ایک اور بات پیش کرتے ہیں اور اس میں آپ کی بہتری ہے.آنحضور نے فرمایا.بتاؤ وہ کیا ہے؟ تو کہنے لگے.ایسا کرو کہ ایک سال آپ ہمارے بتوں کی
پوجا کرو.اور پھر ایک سال ہم آپ کے معبود کی پرستش کریں گے.حضرت نے فرمایا.ٹھہر
جاؤ.اس کا جواب میں خدا سے پا کر تم کو بتلاؤں گا.پس یہ وحی الہی نازل ہوئی.لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ
لا أعبد میں تمہارے بتوں کی نہ اب پوجا کرتا ہوں اور نہ آئندہ کروں گا.اس جگہ
بتوں کی عبادت کی نفی حرف لا کے ساتھ کی گئی ہے.کیونکہ حرف لا کی نفی حال اور استقبال ہر دو
پر مشتمل ہے.نہ اب اور نہ آئندہ.مَا تَعْبُدُونَ.جو کچھ تم عبادت کرتے ہو.ما اسم مبہم ہے.اور مشرکوں کے معبودوں
کے ابہام کی طرف اشارہ کرتا ہے.کیونکہ مشرک اپنی خواہش بے جا کے سبب خود اپنے اندر
ایک شک وشبہ میں پڑا ہوا ہے.اور ہر روز نیابت اپنے لئے تراشتا ہے....رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ طیب اور مبارک کے متعلق غیر اللہ کی عبادت
سے بیزاری اس جگہ حال اور مستقبل میں دو بار کر کے جو بیان کی گئی ہے اس میں اشارہ ہے کہ
990
Page 999
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے معصوم ہیں کہ ان کی حالت میں کجی اور انحراف اور بدی
کی طرف تبدیلی واقع ہو.پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معبود زمانہ گزشتہ میں بھی ایک
خدا ہی تھا اور اب بھی وہی ہے اور آئندہ بھی وہی ایک ہوگا....اس سورۃ شریف کا اول اس کے آخر کے مطابق ہے.نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
کہا میں واحد خدا کی پرستش کرتا ہوں اور تمہارے معبودوں کی پرستش نہ کی ہے، نہ کرتا ہوں اور
نہ کروں گا.اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ توحید اور اخلاص کا دین مجھے ہی عطا ہوا.اور ایسا ہی تمہیں تمہارا
حساب بھگتنا پڑے گا اور مجھے اپنا.پس میری نصرت کی جائے گی اور میری عزت کی جائے گی
اور میں تمہارے شہروں کو فتح کروں گا اور اس کے ساتھ دوسرے شہروں کو بھی فتح کروں گا.اور لوگ اللہ تعالیٰ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوں گے اور تم میری مخالفت میں اپنے مال
بھی خرچ کرو گے اور پھر بھی مغلوب رہو گے.پس یہ دونوں دین بلحاظ اصول اور فروع اور نتیجہ
کے یکساں نہیں رہیں گے.پس اس سورۃ شریف میں کفر سے پوری بیزاری ظاہر کی گئی ہے.ا قل.کہہ دے.بول.یہ خطاب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے.اور آپ کی طفیل
تمام مسلمانوں کو ہے کہ ایسے کفار کو جو کفر پر ایسے بچے ہیں کہ نہ پہلے کبھی انہوں نے خالص اللہ
تعالیٰ کی عبادت کی اور نہ آئندہ ان سے ایسی امید ہوسکتی ہے.ان کو کہہ دو کہ تم جو اپنے کفر پر
ایسے پکے ہو اور مسلمانوں کو برا سمجھتے ہو اس سے حق اور باطل میں تمیز ہو جائے گی کہ تم اپنے دین
پر پگے رہو اور ہم اپنے دین پر پکے ہیں.نتیجہ خود ظاہر کر دے گا کہ کون سچا اور منجانب اللہ ہے اور
کون جھوٹا اور شیطانی راہ پر ہے.چونکہ اس سورۃ شریف میں کفار کو مخاطب کیا گیا ہے اور ان کے مذہب کے بطلان کے
واسطے ایک زبر دست دلیل پیش کی گئی ہے.اسی واسطے یہ کلام بطور ایک چینج کے خدا تعالیٰ
نے اپنے رسول کو القاء کیا اور اسی واسطے اس کے شروع میں لفظ قُلی آیا ہے.يَا أَيُّهَا الكَفِرُونَ سنواے منکرو! اس میں تین حروف ایک جگہ جمع کئے گئے ہیں.991
Page 1000
تیا ( حرف ندا ) آئی ( تخصیص کے لئے ہے ) اور ھا ( تنبیہ کا حرف ہے خبردار کرنے کے
لئے ) جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نہایت تاکید کے ساتھ اچھی طرح منکروں کے کان کھول کھول
کران کو یہ پیشگوئی سنائی گئی تھی کہ تم کو تمہارے اس طریقہ کا بدلہ ملنے والا ہے.اور تم دیکھ لو گے
که خداوند تعالیٰ توحید کے پرستاروں کو تمہارے مقابلہ میں کس طرح کامیابی عطا کرے گا.حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یا نداءُ النَّفْس ہے اور آئی نِدَاءُ الْقَلْبِ
ہے اور هَانِدَاءُ الرُّوح ہے.گویا نفس ، رُوح اور قلب ہر سہ کو مخاطب کیا گیا ہے.بعض نے لکھا ہے کہ یا حرف نداء غائب کے واسطے ہے.اور آئی حرف نداء حاضر کے
واسطے اور ھا تنبیہ کے واسطے.کیا حاضر، کیا غائب، سب کو نہایت تاکید کے ساتھ مخاطب کیا
گیا ہے.انبیاء کی دعوت ہمیشہ اسی طرح نہایت تاکید کے ساتھ بار بارلوگوں کو بلا کر اور مخاطب کر
کے پہنچائی جاتی ہے.چنانچہ اس کی نظیر خود اس زمانہ میں خدا تعالیٰ نے ہمارے واسطے پیدا کر
دی ہے.خدا کا مسیح کس قوت اور زور کے ساتھ دنیا کی تمام قوموں کے درمیان توحید کا وعظ کر
رہا ہے.نہ ایک دفعہ کہہ کر وہ خاموش ہو جاتا ہے.بلکہ بار بار ہر ایک ذریعہ سے خدا کا پیغام
دنیا کو پہنچاتا ہے.نہ صرف ایک زبان میں بلکہ اردو، عربی، فارسی اور انگریزی، پشتو وغیرہ
زبانوں میں اس کی تبلیغ کا آوازہ دنیا کے چار کونوں تک پہنچ رہا ہے.رسالوں میں.اخباروں
میں.اشتہاروں میں.زبانی تقریروں قلمی تحریروں میں.غرض کوئی ذریعہ تبلیغ کا اٹھا نہیں
رکھا گیا.اور آج دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں جہاں کے لوگ اس مسیح کے نام سے اور اس کے
دعوے سے ناواقف ہوں.خدا کے برگزیدوں کی ہمیشہ سے یہ ہی سنت ہے کہ وہ کھول کھول کر
اور پھاڑ پھاڑ کر خدا کا حکم دنیا جہان کو پہنچادیتے ہیں اور اس کے حکم کے پہنچانے میں نہ وہ کسی
دشمن کی دشمنی کی پرواہ کرتے اور نہ کسی مخالف کی مخالفت سے کبھی ڈرتے ہیں.نادان ان کے
مقابلہ میں اُٹھتے اور جوش دکھاتے ہیں.پھر تھک کر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر ناامید ہو کرنا کام
992
Page 1001
مرجاتے ہیں.پر وہ خدا کے بندے ہر روز اپنا قدم آگے بڑھاتے ہیں اور خدا کی تائید سے
کامیاب ہو کر رہتے ہیں.یه سوره شریف بقول ابن مسعود و حسن و عکرمہ مگی ہے.اس زمانہ میں نازل ہوئی تھی
جبکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہنوز مکہ معظمہ میں قیام رکھتے تھے.اس سورہ کی پیشین گوئی سے
بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سورۃ ایسے وقت میں نازل ہوئی تھی جب کہ کفار اپنے زور پر تھے.اور اپنے بتوں کی حمایت اور ان کی پرستش میں بڑے یقین کے ساتھ مصروف تھے اور گمان
کرتے تھے کہ اسلامی سلسلہ ایک چند روزہ بات ہے جو جلدی ہم لوگ اپنی قوت و زور کے
ساتھ نیست و نابود کر دیں گے.اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت کی اصل کیفیت
نہ سمجھ کر ان میں سے چند آدمی جیسا کہ ابو جہل.عاص بن وائل اور ولید بن مغیرہ.آسو د بن
عبد يغوث وغیرہ نے آپ کے پاس پیغام بھیجا کہ ہمارے بتوں کی مذمت کرنا اور ان کو بُرائی
سے یاد کرنا چھوڑ دو.اور اس کے عوض میں ہم آپ کو اس قدر مال دیں گے کہ مکہ میں آپ سے
زیادہ بڑا کوئی مالدار نہ ہو وے.یا اگر آپ چاہیں تو ہمارے قبائل میں سے سب سے زیادہ
خوبصورت عورت جو آپ کو پسند ہو آپ لے لیں اور اگر آپ کو ان دونوں باتوں میں سے کوئی
بات پسند نہ ہو تو پھر تیسری بات یہ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ اس طرح سے صلح کرلیں کہ ایک
سال ہمارے بتوں کی پرستش کریں تو پھر دوسرے سال ہم آپ کے اللہ کی عبادت کریں گے.اس طرح برابر تقسیم ہوتی رہے گی اور کسی کو شکایت کا موقعہ نہ رہے گا.معلوم ہوتا ہے کہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ لوگ کیسے جاہل ہیں کہ نہیں سمجھتے کہ میں کس خوبیوں
سے بھرے ہوئے اسلام کی طرف ان کو بلاتا ہوں اور کس قادر وتوا ناحی و قیوم معبود حقیقی کے
قرب کے حصول کا ذریعہ ان کے آگے پیش کرتا ہوں اور کیسی دائمی خوشی اور ابدی راحت کا تحفہ
ان کے واسطے تیار کرتا ہوں جس کے عوض یہ مجھے نا پائیدار مال اور عورت کے چند روزہ محسن کا
لالچ دیتے ہیں.اور پتھر کے آگے سرجھکانے کو کہتے ہیں جو انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے
993
Page 1002
گھڑے اور بنائے ہیں.چونکہ آپ کو ان لوگوں کی خیر خواہی کے واسطے بڑا درد تھا.جس کو
خدائے علیم نے ان الفاظ میں ظاہر کیا ہے کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا
مُؤْمِنِينَ (الشعراء 4) کیا تو اس غم میں کہ یہ ایمان نہیں لاتے اپنی جان کو ہلاک کر دے گا.آپ نے کفار کے ایسے جاہلانہ سوال پر دردمند ہو کر یہی بہترسمجھا کہ اس کے جواب کے واسطے
اپنے معبود حقیقی کی طرف توجہ کریں اور یہی طریقہ ہمیشہ سے انبیاء کے حصہ میں آیا ہے.چنانچہ
آپ کی توجہ کے بعد خدا تعالیٰ سے کفار کے جواب میں یہ سورۃ شریف نازل ہوئی جس سے
کفار کی تمام امید میں ٹوٹ گئیں.اس قسم کے صلح کے شرائط عموما کفار انبیاء کے سامنے بہ سبب
اپنی جہالت کے پیش کیا کرتے ہیں.چنانچہ اس زمانہ میں بھی خدا کے مُرسل حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مخالفوں نے یہ بات
کہی کہ ان کے اتقاء اور علم اور عمل میں ہم کو کوئی شک نہیں.بے شک یہ ولی اللہ ہیں اور ہم
ان کو ماننے کے واسطے تیار ہیں.صرف مسیح ہونے کا دعوی نہ کریں اور بس.تعجب ہے کہ ان لوگوں کی عقل پر کیسے پتھر پڑ گئے.کیا وہ شخص جو متقی اور عالم اور ولی اللہ
مانا جا سکتا ہے اس کی نسبت یہ کلمہ بھی کسی عقل کی رُو سے کہنا جائز ہوسکتا ہے کہ اس نے دعویٰ
نبوت اور مسیحیت کا از خود کر دیا ہے.اور خدا پر افتراء باندھا ہے؟ کیا مفتری علی اللہ متقی اور
ولی اللہ ہو سکتا ہے؟ ہاں کفار کے ساتھ ایک اور صورت صلح کی ہو سکتی ہے اور
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کفار کے ساتھ کی تھی.جس کی شرط یہ تھی کہ کفار مسلمانوں پر
حملہ نہ کریں اور نہ اُن لوگوں کی امداد کریں جو مسلمانوں پر نا جائز حملہ کرتے رہتے ہیں.اور ایسے
ہی مسلمان نہ ان کو کسی قسم کی تکلیف دیں گے اور نہ ان کے تکلیف دہندوں کی کوئی حمایت
کرے گا بلکہ ہر طرح سے ان کے بچاؤ کی کوشش کریں گے.اسی رنگ میں صلح حضرت
مسیح موعود نے بھی مخالف عیسائیوں، آریوں ، ہندؤوں اور دیگر اقوام کے سامنے پیش کی تھی کہ
چند سالوں تک جو معین کئے جاویں یہ قومیں مسلمانوں کے خلاف کوئی کتاب نئی یا پرانی شائع نہ
994
Page 1003
کریں اور ایسا ہی مسلمان اس عرصہ میں کوئی کتاب ان مذاہب کی تردید میں نہ لکھیں گے.ہاں ہر ایک مذہب کے عالم کو یہ اختیار ہوگا کہ صرف اپنے مذہب کی خوبیاں بیان کرتے
رہیں.کوئی کتاب لکھے جس میں یہ دکھائے کہ اس مذہب پر چلنے سے کیا کیا فوائد حاصل ہو
سکتے ہیں لیکن کسی دوسرے مذہب کا کچھ ذکر نہ کریں.مذہبی جنگوں کے خاتمہ کے واسطے اور
آئے دن کے جھگڑوں اور تنا زعوں کے مٹانے کے لئے یہ نہایت ہی احسن طریقہ تھا مگر افسوس
ہے کہ لوگوں نے اس طرف توجہ نہ کی.غرض اس قسم کی صلح تو انبیاء کی سنت کے مطابق ہے.لیکن یہ بات کہ مداہنہ کے طور پر اور منافقت سے کچھ تم ہمارے عقائد کو مان لو اور کچھ ہم
تمہارے عقائد کو مان لیں.ایسا طریقہ خدا کے سچے رسول کبھی اختیار نہیں کر سکتے.بعض لوگ اس سورۃ شریف کے یہ معنے سمجھ کر اس کو منسوخ سمجھتے ہیں کہ کفار کو ان
کے دین پر رہنے کی اس میں اجازت دی گئی ہے کہ وہ بیشک اپنے دین پر رہیں اور مسلمان ان
کے ساتھ کوئی تعریض نہیں رکھیں گے.لیکن جب جہاد کے متعلق آیات نازل ہوئیں تو پھر یہ
سورۃ منسوخ ہو گئی.یہ بات بالکل غلط ہے.قرآن شریف کی کوئی سورت اور سورت کا کوئی
حصہ منسوخ نہیں ہے.سب کا سب ہمیشہ کے واسطے بنی نوع کے عمل کے لئے عمل کرنے
اور فائدہ اٹھانے کے واسطے ہے.قیامت تک قرآن شریف کا ایک نقطہ بھی منسوخ نہیں ہو
سکتا.اصل بات یہ ہے کہ مذہب اسلام میں دینی اختلاف کی وجہ سے نہ کوئی لڑائی
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور نہ آپ کے بعد کبھی کسی کو اجازت ہے کہ دینی اختلاف
کی وجہ سے کسی کو قتل کرے.آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں کفار نے جب
مسلمانوں کو سخت دُکھ دیا اور طرح طرح کے ایڈا کے ساتھ پہلے مسلمانوں کو تہ تیغ کرنا شروع
کیا اور بڑی بڑی فوجیں لے کر ان پر چڑھائیاں کیں تو بہت سے صبر اور تحمل کے بعد جب وہ
کسی طرح بھی باز نہ آئے تو خدا تعالیٰ نے مسلمانوں کو اجازت دی کہ ایسے شریروں سے اپنا
بچاؤ کریں اور ان کو شرارت کی سزا دیں.995
Page 1004
جہاد کے واسطے جو کچھ حکم تھا یہی تھا.اور اس زمانہ میں بہ سبب اس کے کہ مذہب کی خاطر
مسلمان کسی ملک میں دُکھ نہیں دیئے جاتے.خود ان کی بھی ضرورت نہیں رہی.سورۃ کافرون
میں تو خود جہاد کے کرنے یا نہ کرنے کا کوئی تذکرہ بھی نہیں.لیکن اگر بہر حال یہ سمجھا ہی جاوے
کہ اس سورۃ شریف میں جہاد کے متعلق کوئی حکم ہے تو وہ جہاد کے جواز کا ہوسکتا ہے.نہ کہ
اس کے نسخ کا.کیونکہ اس سورۃ میں مخالفوں کو ایک چیلنج دیا گیا ہے کہ تم اپنے دین کے ساتھ زور
آزمائی کرو.اور ہم اپنے دین کی قوت کے ساتھ تمہارا مقابلہ کرتے ہیں.پھر دیکھو کہ خدا کس
کو کامیاب کرتا ہے.اور یاد رکھو کہ یہ کامیابی بہر حال اسلام کے واسطے ہے.پس یہ سورت
کسی حالت میں منسوخ نہیں اور نہ کوئی اور حصہ قرآن شریف کا منسوخ ہوا یا ہوسکتا ہے.دين : جزا و سزا کے معنے میں بھی آتا ہے.اور اس کا یہ مطلب ہے کہ تم لوگوں نے
جس طریقہ کو اختیار کیا ہے اس کا بدلہ تم کو بہر حال مل کر رہے گا.جو طریقہ ہم نے اختیار کر لیا
ہے اس کا بدلہ خدا ہم کو ضرور دے گا.حضرت نبی کریم کی ابتدائی تیرہ سالہ مکہ کی زندگی کیسی مشکلات اور مصائب کی زندگی ہے مگر
با ایں کہ آپ بالکل تنہا اور کمزور ہیں.خدا تعالیٰ آپ کی زبان سے اہل مکہ کے بڑے بڑے
اکابر قریش اور سردارانِ قوم کو جو اپنے برابر کسی کو دنیا میں سمجھتے ہی نہ تھے.یوں خطاب کراتا
ہے.قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کمزوری کی حالت میں بھی خدائی
تائید اور نصرت کی وجہ سے جو آپ کے شامل حال تھی اور اس کامل اور سچے علم کی وجہ سے جو
آپ کو خدا کے وعدوں پر تھا.آپ میں ایسی قوت اور غیرت و حمیت موجود تھی کہ آپ تبلیغ
احکام الہی میں ان کے سامنے ہرگز ہرگز ذلیل نہ تھے.بلکہ آپ کے ساتھ خدا کی خاص نصرت
اور حق کا رُعب اور جلال ہوا کرتا تھا.پس اس سے مسلمانوں کو یہ سبق لینا چاہئے کہ حق کے
پہنچانے میں ہرگز ہر گز کمزوری نہ دکھائیں اور دینی معاملات میں ایک خاص غیرت اور جوش
اور صداقت کے پہنچانے میں سچی حمیت رکھیں.996
Page 1005
کافر کا لفظ عرب کے محاورے میں ایسا نہیں تھا جیسا کہ ہمارے ملک میں کسی کو کافر کہنا
گویا آگ لگا دینا ہے.وہ لوگ چونکہ اہلِ زبان تھے.خوب جانتے تھے کہ کسی کی بات کو نہ
ماننے والا اس کا کا فر ہوتا ہے.اور ہم چونکہ آپ کی بات نہیں مانتے اس واسطے آپ ہمیں اس
رنگ میں خطاب کرتے ہیں.قرآن شریف میں خود مسلمانوں کی صفت بھی کفر بیان ہوئی ہے
جہاں فرمایا ہے.يَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ (البقرة 247) معلوم ہوا کہ کفر مسلمان کی بھی ایک
صفت ہے.مگر آجکل ہمارے ملک میں غلط سے غلط بلکہ خطر ناک سے خطرناک استعمال میں
آیا ہے.کسی نے کسی کو کافر کہا اور وہ دست و گریبان ہوا.اصل میں کافر کا لفظ دل دکھانے کے واسطے نہیں تھا.بلکہ یہ تو ایک واقعہ کا اظہار و بیان
تھا.وہ لوگ تو اس لفظ اور خطاب کو خوشی سے قبول کرتے تھے.ا قُل يَأَيُّهَا الكَفِرُونَ.کے معنے ہوئے کہ وے اے کا فرو ہوشیار ہو کر اور توجہ سے میری
بات کوٹن لو.اعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ.میں اُن بتوں کی ، ان خیالات کی ، ان رسوم و رواج کی اور اُن
ظنوں کی فرماں برداری نہیں کرتا جن کی تم کرتے ہو.ان لوگوں میں اکثر لوگ تو ایسے ہی تھے جو رسم و رواج، عادات اور بتوں کی اور ظنوں اور
وہموں کی پوجا میں غرق تھے.ہاں بعض ایسے بھی تھے جو دہر یہ تھے.مگر زیادہ حصہ ان میں سے
اوّل الذکر لوگوں میں سے تھا.خدا کو بڑا خدا جانتے تھے اور خدا سے انکار نہ کرتے تھے.پس
ایسے بھی کافر تھے جو خدا کو بھی مانتے تھے اور بتوں سے بھی الگ تھے.رسم و رواج میں بھی نہ
پڑے تھے.آنحضرت کے پاس آنے کو اور آپ کی فرماں برداری کرنے میں اپنی سرداری
کی ہتک جانتے تھے اور ان کے واسطے ان کا کبر اور بڑائی ہی حجاب اور باعث کفر ہورہی تھی.وَلَا انْتُمْ عَبدُونَ مَا أَعْبُدُ.اور نہ ہی تم میرے معبود کی عبادت کرتے نظر آتے ہو.وَلَا أَنَا عَابِدُ ما عَبدُتُم.اور نہ ہی میں کبھی تمہاری طرز عبادت میں آؤں گا.997
Page 1006
وَلَا أَنْتُمْ عَبدُونَ مَا أَعْبُدُ.اور نہ ہی تم اپنے رسم و رواج ، جتھے اور خیالات ، اپنے
بتوں اور مہنتوں کو چھوڑتے نظر آتے ہو.تو اچھا.پھر ہمارا تمہارا یوں فیصلہ ہوگا کہ لكُم
دِينَكُمْ وَلِى دِينِ.میرے اعمال اور عقائد کا نتیجہ میں پاؤں گا اور تمہارے بدکردار اور عقائد
فاسدہ کی سزا تم کو ملے گی.پھر اُس وقت پتہ لگ جاوے گا کہ کون صادق اور کون کا ذب ہے.اس کا جو نتیجہ نکلا وہ دنیا جانتی ہے.ہر ایک نے سُن لیا ہوگا کہ آنحضرت دنیا سے کس حالت میں
اٹھائے گئے اور آپ کے اتباع کو دنیا میں کیا کچھ اعزاز اور کامیابی نصیب ہوئی اور آپ کے
وہ دشمن کہاں گئے اور ان کا کیا حشر ہوا.کسی کو ان کے ناموں سے بھی واقفیت نہیں.بس یہی
نمونہ اور مابہ الامتیا ز ہمیشہ کے واسطے صادق اور کاذب میں خدا کی طرف سے مقرر ہے.ماخوذ از حقائق الفرقان زیر تفسیر سورة الفيل )
حضرت خلیفہ مسیح الثانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:
حضرت عبد اللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے
تھے قُلْ هُوَ الله احد قرآن شریف کے تیسرے حصہ کے برابر ہے اور قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَفِرُونَ
قرآن کے چوتھے حصہ کے برابر ہے اور آپ کئی دفعہ صبح کی دورکعتوں میں یہ دوسورتیں پڑھا
کرتے تھے.اس حدیث کا یہ بھی مطلب نہیں کہ قرآن کریم کے تیسرے حصہ کے برابر قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ
ہے اور چوتھے حصہ کے برابر قُلْ يَا أَيُّهَا الكَفِرُونَ ہے.کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو باقی قرآن کے
نازل ہونے کی ضرورت کیا تھی؟
اس کا مطلب یہی ہے کہ صداقتیں اپنی جڑ کے لحاظ سے بہت مختصر ہوتی ہیں.مثلاً اگر
مذہب کا خلاصہ نکالا جائے تو اتنا ہی ہوگا کہ خدا تعالیٰ سے محبت اور بندوں سے شفقت.یہی
قرآن کریم سے اور حدیثوں سے دین کا خلاصہ معلوم ہوتا ہے.اب اگر کوئی شخص کہہ دے کہ
بندوں پر شفقت آدھا دین ہے تو اس کے یہ معنے نہیں ہوں گے کہ اس فقرہ کے بعد آدھے
998
Page 1007
دین کی ضرورت نہیں رہتی اور نہ یہ کہنے سے کہ خدا تعالیٰ کی محبت بڑی اہم چیز ہے یہ نتیجہ نکلتا
ہے کہ دین کے نصف حصہ کا ذکر ہو گیا.اب اس کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں.پس قُل
هُوَ الله احد کو تلت قرآن قرار دینا یا قُلْ يَا أَيُّهَا الكَفِرُونَ کو ربع قرار دینے کے معنے یہی
ہیں کہ ان کے مطالب نہایت اہم ہیں.اور اگر ان کے مطالب پر صحیح طور پر غور کیا جائے تو
دین کی بہت سی مشکلات حل ہو جاتی ہیں.مثلاً قُل هُوَ اللهُ أَحَدٌ میں توحید پر زور ہے.حقیقت
یہی ہے کہ توحید مذہب کی جان ہے.اگر کوئی شخص تو حید کو اچھی طرح سمجھ لے تو مذہب کا
بہت سا حصہ اُس پر روشن ہو جاتا ہے اور اس کی فطرت اُسے مذہب کی بہت سی تفصیلات کی
طرف خود را ہنمائی کر دیتی ہے.اسی طرح قُلْ يَا أَيُّهَا الكَفِرُونَ میں مذہب پر استقلال کی
طرف اشارہ کیا گیا ہے.اور اس میں بھی کیا شبہ ہے کہ سچائی کے مان لینے سے سچائی پر قائم
رہنا کم اہم نہیں.جتنی خرابی دنیا میں سچائی کے نہ ماننے سے پیدا ہوتی ہے اتنی ہی یا اس سے
زیادہ خرابی سچائی پر قائم ندرہ سکنے سے پیدا ہوتی ہے.مسند احمد حنبل، مسند ابو داؤد اور سنن ترمذی اور سنن نسائی میں لکھا ہے.نوفل بن معاویہ
الا اشجعی نے ایک دن کہا.یا رسول اللہ ! مجھے وہ بات سکھائیے جو میں بستر پر لیٹتے وقت کہا
کروں.قالَ اقْرَءُ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَفِرُونَ ثُمَّ لَمْ عَلَى خَاتِمَتِهَا فَإِنَّهَا بَرَاءَةٌ مِنَ الشَّرَكِ.آپ نے فرما یا قُلْ يَا أَيُّهَا الكَفِرُونَ پڑھا کرو اور پھر اس کے آخری حصہ کو پڑھتے پڑھتے
سو جایا کرو.کیونکہ ان میں شرک سے بیزاری کا ذکر ہے.اس حدیث سے بھی میرے اُس استدلال کی تصدیق ہو جاتی ہے جو میں نے اوپر کیا ہے.مومن کا یہ پختہ ارادہ کہ وہ کبھی بھی باطل کو قبول نہیں کرے گا اور خواہ کچھ ہو جائے وہ سچ کو نہیں
چھوڑے گا ایک حیرت انگیز طاقت اس کے اندر پیدا کردیتا ہے.اگر اس کے بجائے لوگ یہ
ارادہ کرلیں کہ ہم اپنے سابق خیالات یا اپنے باپ دادا کے خیالات کو نہیں چھوڑیں گے یا
مولویوں کے خیالات کو نہیں چھوڑیں گے تو پھر ان کی تباہی اور بربادی میں کوئی شک وشبہ ہی
999
Page 1008
نہیں رہتا.اسی طرح اس حدیث سے یہ بھی نتیجہ نکلتا ہے کہ انسان جن خیالات پر سوتا ہے وہ
بہت مضبوطی کے ساتھ اس کے ذہن میں راسخ ہو جاتے ہیں.اسلام ہی ہے جس نے یہ نکتہ سب
سے پہلے بیان کیا.مگر مسلمان ہی ہیں جو اس نکتہ کو بھول گئے ہیں.رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم نے
یہ فرمایا کہ جس وقت تم اپنے دنیوی کاموں سے فارغ ہو کر بستر پر لیٹو تو اور تمام باتوں کی طرف سے
توجہ ہٹا کر کچھ دعائیں پڑھا کرو اور انہی کو سوچتے سوچتے سو جایا کرو.اگر انسان سوتے وقت بعض اعلی قسم کی دعائیں اور تسبیح اور تحمید کے کلمات دہراتے ہوئے
اور سوچتے ہوئے سو جائے تو یقیناً اس کے دماغ میں رات کے فارغ اوقات میں وہی خیالات اور
وہی باتیں گھومتی رہیں گی.نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک لمبے عرصہ تک ان خیالات کے دماغ میں گھومنے کی
وجہ سے وہ جڑ پکڑ جائیں گے اور مضبوطی سے قائم ہو جائیں گے اور آسانی سے نکالے نہیں جاسکیں
گے.اور انسان کا ایمان مضبوط ہو جائے گا اور اس کو استقلال کی توفیق ملے گی.حضرت ابن عباس سے روایت کی ہے کہ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
اَلا اَدلُّكُمْ عَلَى كَلِمَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِنَ الْإِشْرَاكِ بِاللَّهِ تَقْرَءُوْنَ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَفِرُونَ عِنْدَ
مَنَامِكُمْ.یعنی رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں جو تم
کو اللہ تعالی کے شرک سے بالکل بچالے.وہ بات یہ ہے کہ سوتے وقت تم قُلْ يَا أَيُّهَا
الكَفِرُونَ پڑھو.خباب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم جب لیٹتے تو قل
يَا أَيُّهَا الكَفِرُونَ پڑھا کرتے تھے ( یعنی ساری سورۃ ) اور ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا تھا کہ آپ
لیٹیں اور قُلْ يَا أَيُّهَا الكَفِرُون کی ساری کی ساری سورۃ نہ پڑھیں.اس سورۃ کے فضائل کے متعلق جبیر بن مطعم سے بھی ایک روایت ہے کہ نبی کریم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اتُحِبُّ يا جُبَيْرُ إِذَا خَرَجْتَ سَفَرًا أَنْ تَكُونَ أَمْثَلَ أَصْحَابِكَ
هَيْئَةً وَاكْثَرَهُمْ زَادًا یعنی اے جبیر کیا تم پسند کرتے ہو کہ جب تم سفر کے لئے نکلو تو اپنے
ساتھیوں میں سے سب سے زیادہ شان تمہارے ساتھ ہو.جبیر نے عرض کیا یا رسول اللہ ہاں!
1000
Page 1009
اس پر آپ نے فرمایا تب تم سفر میں یہ پانچ سورتیں پڑھا کرو.یعنی سورۃ الکافرون سے لے کر
قُلْ أَعُوذُ بِرَتِ النَّاس تک.سورۃ الکافرون سے آخر تک چھ سورتیں ہیں.پس یا تو پانچ کے
یہ معنے ہیں کہ سورہ سبت کو اس
گنتی میں سے آپ نے نکال دیا ہے اور یا پھر الکافرون کے بعد
کی سورتوں کو آپ نے پانچ قرار دیا ہے یا پانچ راوی کی غلطی ہے اور مراد یہ ہے کہ الکافرون
سمیت چھ یا الکافرون کو نکال کر اس کے بعد کی پانچ سورتیں.پھر آپ نے فرمایا جب پڑھنا شروع کرو تو بِسمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ پڑھ کر تلاوت
شروع کیا کرو یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ بسم اللہ الرّحمنِ الرَّحِيمِ ہر سورۃ کا حصہ ہے )
جبیر کہتے ہیں کہ میں مال دار نہ تھا اور جب میں سفر کرتا تھا تو سب ساتھیوں سے بُرا حال میرا
ہوتا تھا.اور سب سے کم زاد میرے پاس ہوتا تھا.مگر اس کے بعد ان سورتوں کی برکت کی وجہ
سے میرا حال سب ساتھیوں سے اچھا ہو گیا اور سب سے زیادہ زاد میرے پاس ہوتا.اس میں کوئی شبہ نہیں کہ قرآن کریم کی سورتوں کے پڑھنے میں برکات ہیں.جو شخص قرآن
کریم پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اُس پر اپنا فضل نازل کرتا ہے مگر
اس کے علاوہ یہ بات بھی ہے کہ ان سورتوں میں زیادہ تر غیر مذاہب کا مقابلہ ہے اور اپنی
کمزوریوں کو دُور کرنے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے اور مصائب کے وقت میں استقلال قائم
رکھنے کی تلقین ہے اور توحید پر زور دیا گیا ہے اور باہمی لڑائی اور جھگڑے سے روکا گیا ہے.اور
جب انسان ان مضامین کو بار بار اپنے ذہن میں لاتا ہے تو اس کے اندر یہ خصلتیں بھی پیدا ہو
جاتی ہیں اور ان خصلتوں کی وقت اور اہمیت بھی اس پر ثابت ہوتی چلی جاتی ہے.اور جب وہ
ان خصلتوں پر عمل کرتا ہے تو غیروں کی نگاہ میں معزز ہوجاتا ہے اور اپنوں کی نگاہ میں اتحاد کا
باعث بن جاتا ہے.جب بھی غیر دیکھیں کہ یہ شخص ہمارے حالات سے مرعوب ہو گیا ہے تو ان
کے حوصلے بڑھ جاتے ہیں اور اس کی قوم کی عزت ان کی نظروں سے گر جاتی ہے.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جبیر سے یہ بات فرمائی کہ تم یہ سورتیں پڑھو تو تمہارا
رعب بڑھ جائے گا.اس سے درحقیقت اسی طرف اشارہ تھا کہ ان سورتوں میں اسلام کی
1001
Page 1010
اور
مرکزی تعلیم کو پیش کیا گیا ہے اور اس پر مخالفت کے باوجود مستقل رہنے کی ہدایت کی گئی ہے
دور جو شخص بھی مخالفانہ ماحول میں اپنے خیالات پر قائم رہنے کی جرات دکھائے گالازمنا وہ اپنی
اور اپنی قوم کی عزت قائم کر دے گا.اور یہ جو فرمایا کہ اس سے تمہارا زادراہ بڑھ جائے گا.اس
میں بھی درحقیقت اسی طرف اشارہ ہے کہ جو شخص دوسروں کے آگے سرنگوں ہونے سے انکار
کر دے گا اسے یہ کبھی خیال نہیں آئے گا کہ کوئی میری خبر گیری کرے گا اور میری مدد کرے گا
اور جب وہ لوگوں کی امداد کے خیال سے اپنے خیالات کو آزاد کر لے گا تو لازمتا وہ حلال روزی
اور باعزت روزی کے لئے کوشش بھی کرے گا.حمد اصمعی کہتے ہیں کہ پہلے زمانہ کے لوگ ( یعنی تابعی اور صحابہ ) کہا کرتے تھے کہ
سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص مُقشقشتان ہیں (یعنی یہ سورتیں نفاق سے بچانے والی ہیں
اور قوت ایمانیہ پیدا کرنے والی ہیں) اور ابو عبیدہ کہتے تھے کہ جس طرح رال
کھجلی کو دور کر کے
تندرست کر دیتی ہے.اسی طرح یہ سورتیں انسان کو شرک سے صحت بخشتی ہیں.(قرطبی)
اس سورۃ میں بتایا گیا ہے کہ ایک زمانہ میں کفر پھر اسلام پر غالب آ جائے گا اور
جہاں تک مادی حالات کا سوال ہے اسلام قریباً قریب ختم ہو جائے گا.لیکن اس وقت پھر
رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم کی روح دوبارہ دنیا میں کسی اپنے مثیل اور شاگرد کے ذریعہ سے
ظاہر ہوگی اور دنیا کو پھر وہی چیلنج دے گی جو پہلے آپ نے دیا تھا اور کہے گی کہ خواہ کتنا زور لگالو
میں کفر سے مغلوب نہیں ہوں گا اور کفر کی باتوں کو تسلیم نہیں کروں گا.یہ وہی زمانہ ہے جس کو
مہدی یا مسیح کا زمانہ کہا جاتا ہے اور جس وقت دجال یا یا جوج و ماجوج نے یعنی عیسائیت کے
مذہبی اور سیاسی ظہور نے اسلام پر غلبہ پانا تھا اور بظاہر اسلام کی شان و شوکت کو مٹا کر
عیسائیت کی حکومت کو مستحکم طور پر قائم کر دینا تھا.یہ سورۃ بتاتی ہے کہ جہاں عام طور پر مسلمان
مغربی خیالات سے متاثر ہو کر اس کے آگے ہتھیار ڈال دیں گے وہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کی روح غیر اسلامی خیالات کے آگے ہتھیار ڈالنے سے گلی طور پر انکار کر دے گی اور
1002
Page 1011
باوجود اس کے کہ تشد د اور زبردستی سے اس زمانہ میں اسلام بالکل کام نہیں لے گا پھر بھی وہ کفر
پر غالب آ جائے گا اور انسانوں کے دل کفر و الحاد سے پاک ہو کر پھر اسلام کی طرف راغب ہو
جائیں گے.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا کہ تو ہر زمانہ کے لوگوں سے یہ کہہ دے یہ ایک واضح
اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم کی قوتِ قدسیہ ہر زمانہ میں دنیا میں
ظاہر ہوتی رہے گی.کبھی چھوٹے پیمانہ پر کبھی بڑے پیمانہ پر.اسی کی طرف رسول کریم صلی اللہ
علیہ وسلم نے اس حدیث میں اشارہ فرمایا ہے کہ ان اللهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمِّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِ
مِائَةِ سَنَةٍ مَن يُجيدُ لَهَا دِينَهَا (ابو داؤد كتاب الملاحم) یعنی اللہ تعالیٰ میری اُمت میں ہر سو
سال کے بعد کوئی نہ کوئی شخص ایسا مبعوث کرے گا جو اس صدی کی غلطیوں کو جو کہ دین کے بارہ
میں لوگوں کو لگ گئی ہوں گی دُور کر دے گا.یہ قُل بھی اسی طرف اشارہ کرتا ہے.گویا اس
حدیث کے مطابق رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم کم سے کم ہر صدی کے سر پر دنیا میں ظاہر ہوں
گے اور وہ لوگ جو آپ کے بتائے ہوئے رستہ کے خلاف چلنے والے ہوں گے اُن کو چیلنج
کریں گے کہ میں تمہارے طریق کو کبھی اختیار نہیں کروں گا جو خدا نے مجھے بتایا ہے اور اس
طرح اسلام ہر زمانہ میں ڈھل ڈھلا کر پھر نیا بن جایا کرے گا.مسیح اور مہدی کے زمانہ میں یہ
بات زیادہ نمایاں طور پر ہونے والی ہے کیونکہ اس زمانہ کے متعلق بہت بڑے فتنوں کی پیشگوئی
ہے یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مَا بُعِتَ نَبِي إِلَّا وَقَدْ انْذَرَ أُمَّتَهُ
الدجال (كتاب الملاحم لابی داؤد باب خروج الدجال یعنی جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے تمام
انبیاء نے دجال کے فتنہ سے اپنی امت کو ڈرایا ہے.اس آیت میں جو یہ امر بیان کیا گیا ہے کہ نہ تم میرے طریق پر عبادت کرو گے.نہ میں
تمہارے طریق پر عبادت کروں گا.یا یہ کہ نہ تم میرے معبود کی عبادت کرو گے.نہ میں تمہارے
معبود کی عبادت کروں گا جیسے مشرکین مکہ پر منطبق ہوتا ہے ویسے ہی باقی دنیا کے کفار پر بھی
1003
Page 1012
منطبق ہوتا ہے.کیونکہ اول تو اسلام کے سوا کوئی مذہب دنیا میں ہے ہی نہیں جو تو حید کامل کو
پیش کرتا ہو.اگر ظاہری رنگ میں توحید کسی مذہب میں پائی بھی جاتی ہے تو وہ مذہب بھی
صفات الہیہ کے بیان کرنے میں قرآن کریم سے بہت اختلاف رکھتا ہے.قل کا لفظ اعلان کے لئے آیا ہے یعنی اس سورۃ کے مضمون کا خوب اعلان کر.یوں تو
سب سورتوں کا مضمون اعلان کے قابل ہے.اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ
بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ (مائده (68) اے رسول جو کلام قرآنی تجھ پر نازل ہوتا ہے وہ سب کا
سب لوگوں تک پہنچا دے.پس قرآن کا کوئی حصّہ چھپانے والا نہیں لیکن بعض مضمون وقت
کے لحاظ سے خوب پھیلانے والا ہوتا ہے اس لئے اُس کی طرف خاص طور پر توجہ دلائی جاتی
ہے.چنانچہ پانچ سورتیں قرآن کریم کی ایسی ہیں جن کے شروع میں قُل کے لفظ آتے ہیں
جس کے یہ معنے ہیں کہ اُن کے مضمون کا خوب اچھی طرح اعلان کر دو.یہ سورتیں سورہ جن.سورۃ کافرون.سورۃ اخلاص.سورہ فلق اور سورہ الناس ہیں.ان سورتوں کے علاوہ کم و بیش
تین سو چھ آیتوں سے پہلے بھی یہ لفظ آتا ہے اور جہاں بھی آتا ہے مابعد کے مضمون کی اہمیت
بتانے کے لئے آتا ہے.قرآن کریم کی آخری تین سورتوں سے پہلے اس لفظ کا استعمال بھی یہی بتاتا ہے کہ چونکہ
قرآن کریم ختم ہو رہا تھا اس کا خلاصہ آخر میں پیش کر دیا گیا اور ان سورتوں کے مضمون کی
اشاعت کی طرف خاص توجہ دلا دی تا کہ خلاصہ کے ذریعہ سے سارے مضمون سے اجمالا لوگ
واقف ہوجائیں.قل کا لفظ ان مضامین یا سورتوں سے پہلے آتا ہے جن کے اعلانِ عام کا ارشاد ہوتا ہے
اور یہ ظاہر ہے کہ کسی امر کا اعلان عام ایک آدمی نہیں کرسکتا.ایسے اعلان کا ذریعہ ایک
جماعت ہی ہو سکتی ہے جو نسلاً بعد نسل یہ کام کرتی چلی جائے تا کہ ہر قوم و ملک کو بھی وہ پیغام پہنچ
جائے.اور ہر نسل اور ہر زمانہ کے لوگوں کو بھی وہ پیغام پہنچ جائے.اگر وحی متلو میں یعنی قرآن
میں قتل کا لفظ نہ رکھا جاتا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ حکم چلتا.آپ کے بعد یہ حکم نہ
1004
Page 1013
چلتا.لیکن جبکہ قرآن کی وحی میں یہ لفظ شامل کر دیا گیا تو اب اس کے متواتر تا قیامت جاری
رہنے کی صورت پیدا ہو گئی.جب اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ قُل
يا أَيُّهَا الْكَفِرُونَ تو کافروں کو مخاطب کر کے کہہ دے کہ اے کا فرو! میں تمہارے معبود کی
عبادت قطعاً نہیں کرتا اور نہیں کر سکتا.تو آپ نے یہ اعلان کافروں میں کر دیا.مگر قل کا لفظ پہلے
نہ ہوتا تو مسلمان سمجھتے یہ محمد رسول اللہ کا کام تھا ختم ہو گیا.لیکن جب آپ نے اپنی وحی مسلمانوں
کوشنائی اور یوں پڑھا قُل يَا أَيُّهَا الكَفِرُونَ تو ہر مسلمان نے سمجھ لیا کہ یہ حکم محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لئے نہ تھا بلکہ میرے لئے بھی تھا کیونکہ میرے سامنے جب وحی
محمد رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے تو اس کے پہلے قُل کہا ہے جس کا مخاطب میں ہی
ہو سکتا ہوں، محمد رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نہیں.کیونکہ وہ تو پڑھ رہے ہیں.سُن تو میں رہا ہوں.پس اُس نے اس حکم کی تعمیل میں یہ پیغام آگے پہنچادیا.لیکن چونکہ قُل کا لفظ وحی میں تھا اُس
نے بھی اگلے شخص کے سامنے اسی طرح پیغام پہنچادیا کہ قتل کا لفظ بھی دہرایا اور اس تیسرے شخص
کے سامنے جب قُل کا لفظ کہا گیا تو اُس نے سمجھ لیا کہ صرف مجھے پیغام نہیں پہنچایا گیا بلکہ مجھ
سے یہ بھی خواہش کی گئی ہے کہ میں آگے دوسروں تک یہ پیغام پہنچا دوں.پھر اس تیسرے آدمی
نے چوتھے کو جب پیغام دیا تو پھر قُل کہا کیونکہ وحی کا حصہ ہے اسے چھوڑ انہیں جاسکتا.اس لفظ
کے سننے سے پانچویں نے بھی سمجھ لیا کہ میں نے ہی اس حکم پر عمل نہیں کرنا بلکہ دوسروں تک بھی
ی حکم پہنچانا ہے.غرض اس طرح تا قیامت اس حکم کے دہرانے کا انتظام کردیا گیا.اس سورۃ میں ایک مضمون کو دو شکلوں میں ادا کیا گیا ہے.اور دودفعہ دہرایا گیا ہے.ایک
حصہ مضمون کا یہ ہے کہ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ.جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی میں عبادت
نہیں کرتا.اور دوسرا حصہ اس کا یہ ہے کہ وَلا أَنْتُمْ عَبدُونَ مَا أَعْبُدُ جس کی میں عبادت کرتا
ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے.اور تیسری بات یہ کہی گئی ہے کہ وَلَا انا عبد ما عبدتم
نہ میں اس کی عبادت کرتا ہوں جس کی تم عبادت کر چکے ہو.اور چوتھی بات یہ کہی گئی ہے کہ
وَلا أَنْتُمْ عَبدُونَ مَا اعْبُدُ نہ تم عبادت کرتے ہو یا کرو گے جس کی میں عبادت کرتا ہوں.1005
Page 1014
بظاہر اس میں ایک مضمون کو دو دفعہ دہرا دیا گیا ہے.ایک حصہ کو تو الفاظ میں تغیر قلیل کر کے
دہرایا گیا ہے اور دوسرے حصہ کو جوں کا توں دُہرا دیا گیا ہے.قرآن کریم میں تو تکرار نہیں ہوا
کرتی.پھر ایسا کیوں کیا گیا؟
چونکہ خدا تعالیٰ کے کلام میں فضول تکرار نہیں ہوسکتا.اور چونکہ ما کے دو معنے ہو سکتے ہیں.موصولہ کے بھی اور مصدریہ کے بھی.اللہ تعالیٰ نے وسعت معانی پیدا کرنے کے لئے آیتوں
کے پہلے جوڑے میں ماموصولہ استعمال کیا ہے اور دوسرے جوڑے میں مصدر یہ تو تکرار کا سوال
اُڑ جاتا ہے.اس کے مطابق آیات کے یہ معنے ہو جاتے ہیں کہ میں کبھی عبادت نہ کروں گا اس
کی جس کی تم عبادت کرتے ہو اور نہ تم کبھی عبادت کرو گے ، نہ کر سکتے ہو اُس کی جس کی میں
عبادت کرتا ہوں.اور اسی طرح میں عبادت نہیں کروں گا یا عبادت نہیں کرسکتا اُس طریق پر
جس طریق پر تم عبادت کرتے ہو.اور نہ تم عبادت کرو گے یا کر سکتے ہو اس طریق پر جس طریق
پر میں عبادت کرتا ہوں.ان معنوں کے رُو سے سب تکرار مٹ جاتی ہے اور ہر ہر لفظ اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے اور اس
کی واضح غرض اور مقصد نظر آتا ہے.جہاں تک تاریخی واقعات کا سوال ہے.یہ تو درست ہے کہ نہ صحابہؓ نے کبھی بتوں کی پوجا
کی اور نہ کبھی کفار کے طریق عبادت کو اختیار کیا.مگر دوسرا حصہ تاریخی شواہد کے خلاف معلوم
ہوتا ہے.کیونکہ ہزار با کفار نے ایمان لا کر خدائے واحد کی بھی عبادت کی اور مسلمانوں کے
طریق عبادت کو بھی اختیار کیا.پس بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ مضمون غلط ہو گیا.پس لازماً ان آیات میں کسی اور مضمون کا ذکر ہے اور وہ یہ ہے کہ اس میں مسلمانوں اور
مشرکوں کی فطرت کا ذکر کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ مسلمان فطرۃ توحید کی طرف مائل ہے
اور کافر نے ایک لمبی رسم و عادت کی وجہ سے مشرکانہ فطرت پالی ہے.اس لئے وہ اپنی عادت
اور رسم کی وجہ سے شرک کی طرف تو مائل ہوسکتا ہے.لیکن تو حید کی طرف نہیں جاسکتا.پس در حقیقت وَلا أَنْتُمْ عَبدُونَ مَا أَعْبُدُ میں یہ پیشگوئی تھی کہ مکہ والے رسول کریم
1006
Page 1015
صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اختیار نہیں کریں گے.ان کے مسلمان ہونے کی وجہ سے وہ
پیشگوئی جھوٹی نہیں نکلی.کیونکہ وہ مسلمان اپنی مرضی سے نہیں ہوئے.بلکہ اِنَّ شَانِقَك
هُوَ الابتر کی پیشگوئی کے ماتحت خدا تعالیٰ نے ان کو پکڑ کر مسلمان کیا اور خدائی تصرف کے
ماتحت وہ ایمان لائے.پس عرب کا مسلمان ہو جانا قرآن کریم کے دعوی کے خلاف نہیں بلکہ
قرآنی دعویٰ کی تصدیق ہے.اسی طرح میں نے یہ بیان کیا تھا کہ اس سورۃ کے بعد کی جو سورۃ ہے وہ بھی ان دعاوی
کی دلیل ہے جو قُلْ يَا أَيُّهَا الكَفِرُونَ کے شروع میں بیان کئے گئے ہیں.لا قُلْ يَا أَيُّهَا الكَفِرُونَ کے بعد کی یہ سورۃ ہے کہ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَ الْفَتْحُ وَرَأَيْتَ
النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبَّكَ وَ اسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا یعنی
ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت تجھے حاصل ہوگی اور عرب پر غلبہ تجھے عطا ہو
جائے گا اور تو دیکھے گا کہ فوج در فوج عرب لوگ دین اسلام میں داخل ہوں گے.یہ آیت بھی
سورۃ کافرون کی اس پہلی آیت کی دلیل ہے کہ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَفِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا
تعْبُدُونَ.یہ ظاہر ہے کہ جب باوجود کمزوری کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ
دشمنانِ اسلام پر فتح بخشے گا اور ہزاروں ہزار آدمی مسلمان ہو جائیں گے.تو اس نشان کے دیکھنے
کے بعد کوئی مسلمان کفار کی طرف جاہی کس طرح سکتا ہے.یہ تو روحانی بات ہوئی.ظاہری
سبب کو بھی اگر دیکھو تو انسان اگر کسی کی طرف جاتا ہے تو لالچ کی وجہ سے جاتا ہے.جب اسلام
کو غلبہ حاصل ہو جائے گا اور کفار خود مسلمانوں کے محتاج ہو جائیں گے تو ایسا کون بیوقوف
مسلمان ہو سکتا ہے جو ان مقہور اور مغلوب کفار کے ساتھ ملے اور فاتحین کا ساتھ چھوڑ دے؟ پس
سورۃ کوثر بھی جو اس سے پہلے ہے اور سورہ نصر بھی جو اس کے بعد ہے دونوں سورۃ کافرون کی
پہلی آیتوں کے لئے بطور دلیل ہیں.اسی طرح اس سورۃ کا جو دوسرا حصہ ہے کہ وَلَا أَنتُم
عبدُونَ مَا أَعْبُدُ اس کا بھی حل إِذَا جَاء نَصْرُ الله وَ الْفَتْحُ سے ہوجاتا ہے.یعنی کفار اپنی
1007
Page 1016
فطرت کے لحاظ سے تو شرک پر ہی قائم تھے.مگر جب نصرت اور فتح کے ذریعہ سے اسلام کی
صداقت روز روشن کی طرح ظاہر ہو گئی تو ان کو حالات نے مجبور کر کے اسلام کی طرف دھکیل
دیا.پس با وجود ان کے اسلام لے آنے کے وَلا أَنتُمْ عَبدُونَ مَا أَعْبُدُ والی آیت جھوٹی
نہیں ہوئی بلکہ سورۃ کوثر بھی سچی.سورہ نصر بھی سچی اور سورۃ کافرون بھی سچی ہوئی.لَكُمْ دِينَكُمْ وَلِيَ دِينِ
سورۃ کافرون کی پہلی پانچ آیات میں آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم اور آپ کے متبعین کو
یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اعلان کر دیں کہ کفار کے ساتھ ان
کا اتحاد فی العبادۃ ناممکن ہے.زیر تفسیر
آیت لَكُمْ دِينَكُمْ وَلِی دِيْنِ میں ایسا اعلان کرنے کا سبب بتایا گیا ہے.اور یہ واضح کیا گیا
ہے کہ محمد رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم اور آپ کے متبعین کا یہ اعلان دھینگا مشتی کا فعل نہیں.نہ
کسی عناد کے نتیجہ میں ایسا کیا گیا ہے.بلکہ یہ اعلان اس بات کا نتیجہ ہے کہ کفار کا دین اُن
کے لئے عبادت کا اور طریق مقرر کرتا ہے اور محمد رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم اور آپ کے متبعین کا
دین اُن کے لئے عبادت کا اور طریق مقرر کرتا ہے.اور چونکہ ہر دوطریق کار میں زمین و آسمان
کا فرق ہے.اس لئے دونوں فریق کا اجتماع فی العبادة ناممکن ہے.سورۃ کافرون کی ابتدائی
آیات میں پہلے ایک اصولی فیصلہ کا اعلان کیا گیا ہے.اور پھر اس اعلان کی دلیل
لَكُمْ دِينَكُمْ وَلِی دِینِ کے الفاظ میں بیان کی گئی ہے.لغات میں لفظ دین کے گیارہ معنے لکھے گئے ہیں اور وہ سارے کے سارے اس آیت پر
چسپاں ہوتے ہیں اور ان معنوں کو چسپاں کرنے کے بعد یہ مضمون واضح ہو جاتا ہے کہ کس
طرح اس سوال کو جو قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَفِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ کے بعد طبعا دل میں پیدا ہوتا
تھا شامل کر دیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ محمد رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم اور آپ کے متبعین مجبور
ہیں کہ وہ اعلان کر دیں کہ وہ اپنے مذہب کے اصولِ عبادت کو چھوڑ کر کفار کے ساتھ
متحد فی العبادۃ نہیں ہو سکتے کیونکہ اس کی زبردست وجوہات ہیں جو اختصارا لفظ دین میں ہی
1008
Page 1017
بیان کر دی گئی ہیں اور جن کا ہم ذیل میں ذکر کرتے ہیں.اول مسلمان جس قادر و قیوم ہستی کو مانتے ہیں اُن کے نزدیک اس کی اطاعت کے اصول
اور ہیں اور کافروں کے نزدیک اُن کے معبودوں کی پیروی کے اصول اور.(دین بمعلی
الطاعَةُ)
دوم.مسلمانوں کا طریق عبادت اور ہے اور کافروں کا طریق عبادت اور.(دين بمعنى ما
يُعْبَدُ بِهِ الله)
سوم.مسلمانوں کے اصول حکومت اور ہیں اور کافروں کے اور.(دین بمعنى السُّلْطَانُ وَ
الْمُلْكُ وَالْحُكْمُ
چہارم.مسلمانوں کے نزدیک تقویٰ اور نیکی اور بدی کی تعریف اور ہے اور کافروں کے
نزدیک اور.اسی طرح مسلمانوں کے نزدیک حلال اور حرام کے اصول اور ہیں اور کافروں
کے نزدیک اور.(دِين بمعنى الْوَرَعُ وَالْمَعْصِيَةُ)
پنجم.مسلمانوں کے لوگوں سے معاشرت کے اصول اور ہیں اور کافروں کے اور.(دین
بمعنى الشيرَةُ)
ششم.مسلمانوں کی تدبیر اور ہے اور کافروں کی اور.(دین بمعنی التدبير)
ہشتم.مسلمانوں کے روز مرہ کے کاموں کے اصول اور ہیں اور کافروں کے اور.(دین
بمعنى الحال)
گو بالكُمْ دِينُكُمْ وَلِی دِيْنِ میں یہ بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں اور کافروں کے نہ اصول ملتے
ہیں.اور نہ طریق کار.اس لئے مسلمانوں کی طرف سے یہ اعلان کہ ہم کفار کے ساتھ عبادت
میں اتحاد نہیں کر سکتے بالکل صحیح اور درست ہے اور اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوسکتا.( مزید تفصیلات کے لئے ملاحظہ ہو تفسیر کبیرزیر سورۃ الکافرون )
خلاصہ کلام یہ کہ سورۃ کافرون میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ سبق سکھایا ہے کہ انہیں
1009
Page 1018
یادرکھنا چاہئے کہ ان کی شریعت ہر طرح سے اکمل اور اعلی ہے.اُن کے عبادت کے طریق
دوسرے مذاہب کی عبادت کے طریقوں سے افضل ہیں.اُن کا معاشرہ اعلیٰ درجہ کا ہے.اُن
کے حکومت کے اصول بہترین ہیں.اس کا نظام جماعت نہایت عمدہ ہے اور ان کا مقصد حیات
نہایت ہی مبارک ہے.پس ان باتوں کے حامل شخص کا فرض ہے کہ وہ ہر موقع پر کفر کے
سامنے ڈٹ جائے اور اسلام کی فضیلت کو ثابت کرے اور کبھی کسی رنگ میں بھی کفر سے مرعوب
اور متاثر نہ ہو.کیونکہ اگر وہ ایسا کرے گا تو اس کی دنیا تباہ ہوجائے گی.اور اُسے کبھی بھی کامل
نظام حاصل نہیں ہو گا پس مسلمان کا اس معاملے میں دوسروں سے علیحدہ ہونا ضد کی وجہ سے نہیں
ہوگا.بلکہ بنی نوع انسان کی خیر خواہی اور ترقی کے لئے ہوگا.اس کے مقابلے میں دشمنوں کا ایسا
پاکیزہ نظام سے الگ ہونا یا تو ضد کی وجہ سے ہوگا.یا بنی نوع انسان کی ترقی سے آنکھیں بند
کرنے کی وجہ سے ہوگا.ماخوذ از تفسير كبير زير سورة الكافرون)
1010
Page 1019
XXXXXXXX
بسمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ
وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي
دِيْنِ اللهِ أَفْوَاجًان
فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرُهُ
إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا
سورة النصر
1 - (میں) اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا
( اور ) بار بار رحم کرنے والا ہے( پڑھتا ہوں )
2.جب اللہ کی مدد اور کامل غلبہ آ جائے گا.3.اور تو اس بات کے آثار دیکھ لے گا کہ اللہ کے
دین میں لوگ فوج در فوج داخل ہوں گے.4.اس وقت تو اپنے رب کی تعریف کے ساتھ
( ساتھ ) اس کی پاکیزگی بیان کرنے میں بھی مشغول
ہو جائیو اور ( مسلمانوں کی تربیت میں جو کوتاہیاں
ہوئی ہوں ان پر ) اس ( خدا ) سے پردہ ڈالنے کی
دعا کیجیو.وہ یقیناً اپنے بندے کی طرف رحمت کے
ساتھ کوٹ کوٹ کر آنے والا ہے.1011
Page 1020
حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں:
جبکہ آنے والی مدد اور فتح آگئی جس کا وعدہ دیا گیا تھا اور تُو نے دیکھ لیا کہ لوگ
فوج در فوج دین اسلام میں داخل ہوتے جاتے ہیں.پس خدا کی حمد اور تسبیح کر.یعنی یہ کہہ کہ یہ
جو ہوا وہ مجھ سے نہیں بلکہ اُس کے فضل اور کرم اور تائید سے ہے.اور الوداعی استغفار کر کیونکہ
وہ رحمت کے ساتھ بہت ہی رجوع کرنے والا ہے.استغفار کی تعلیم جو نبیوں کو دی جاتی ہے اس کو عام لوگوں کے گناہ میں داخل کرنا عین حماقت
ہے.بلکہ دوسرے لفظوں میں یہ لفظ اپنی نیستی اور تذلل اور کمزوری کا اقرار اور مدد طلب کرنے
کا متواضعانہ طریق ہے.چونکہ اس سورۃ میں فرمایا گیا ہے کہ جس کام کے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف
لائے تھے وہ پورا ہو گیا یعنی یہ کہ ہزار ہا لوگوں نے دین اسلام قبول کر لیا.اور یہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی طرف بھی اشارہ ہے.چنانچہ اس کے بعد آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم ایک برس کے اندر فوت ہو گئے.پس ضرور تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس
آیت کے نزول سے جیسا کہ خوش ہوئے تھے غمگین بھی ہوں.کیونکہ باغ تو لگایا گیا مگر ہمیشہ کی
آب پاشی کا کیا انتظام ہوا.سو خدا تعالیٰ نے اسی غم کے دُور کرنے کے لئے استغفار کا حکم دیا.کیونکہ لغت میں مغفرت ایسے ڈھانکنے کو کہتے ہیں جس سے انسان آفات سے محفوظ رہے.اسی
وجہ سے مغْفَرُ جو خود کے معنی رکھتا ہے اسی میں سے نکالا گیا ہے.اور مغفرت مانگنے سے یہ
مطلب ہوتا ہے کہ جس بلا کا خوف ہے یا جس گناہ کا اندیشہ ہے خدا تعالیٰ اس بلا یا اس گناہ کو
ظاہر ہونے سے روک دے اور ڈھانکے رکھے.سواس استغفار کے ضمن میں یہ وعدہ دیا گیا کہ
اس دین کے لئے غم مت کھا.خدا تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرے گا اور ہمیشہ رحمت کے ساتھ
1012
Page 1021
اس کی طرف رجوع کرتا رہے گا اور ان بلاؤں کو روک دے گا جو کسی ضعف کے وقت عائد حال
ہوسکتی ہیں.اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں نہایت درجہ کا یہ
جوش تھا کہ میں اپنی زندگی میں اسلام کا زمین پر پھیلنا دیکھ لوں اور یہ بات بہت ہی نا گوار تھی کہ
حق کو زمین پر قائم کرنے سے پہلے سفر آخرت پیش آوے.سو خدا تعالی اس آیت میں
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دیتا ہے کہ دیکھ میں نے تیری مراد پوری کر دی.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم در حقیقت ایسے وقت میں آئے تھے جس وقت میں ایک سچے اور
کامل نبی کو آنا چاہئے.پھر جب ہم دوسرا پہلو دیکھتے ہیں کہ آنجناب صلعم کس وقت واپس
بلائے گئے تو قرآن صاف اور صریح طور پر ہمیں خبر دیتا ہے کہ ایسے وقت میں بلانے کا حکم ہوا
کہ جب اپنا کام پورا کر چکے تھے.یعنی اس وقت کے بعد بلائے گئے جبکہ یہ آیت نازل ہو چکی
کہ مسلمانوں کے لئے تعلیم کا مجموعہ کامل ہو گیا اور جو کچھ ضروریات دین میں نازل ہونا تھا وہ
سب نازل ہو چکا اور نہ صرف یہی بلکہ یہ بھی خبر دی گئی کہ خدا تعالی کی تائید میں بھی کمال
کو پہنچ
گئیں اور جوق در جوق لوگ دین اسلام میں داخل ہو گئے.اور یہ آیتیں بھی نازل ہوگئیں کہ
خدا تعالیٰ نے ایمان اور تقویٰ کو ان کے دلوں میں لکھ دیا اور فسق و فجور سے انہیں بیزار کر دیا اور
پاک اور نیک اخلاق سے وہ منصف ہو گئے اور ایک بھاری تبدیلی ان کے اخلاق اور جلن اور
روح میں واقع ہوگئی.تب ان تمام باتوں کے بعد سورۃ النصر نازل ہوئی جس کا ماحصل یہی ہے
کہ نبوت کے تمام اغراض پورے ہو گئے اور اسلام دلوں پر فتحیاب ہو گیا.تب آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور پر اعلان دے دیا کہ یہ سورت میری وفات کی طرف اشارہ کرتی
ہے بلکہ اس کے بعد حج کیا اور اس کا نام حجۃ الوداع رکھا اور ہزار بالوگوں کی حاضری میں ایک
اونٹنی پر سوار ہو کر ایک لمبی تقریر کی اور کہا کہ سنو! اے خدا کے بندو! مجھے میرے رب کی طرف
سے یہ حکم ملے تھے کہ تا میں یہ سب احکام تمہیں پہنچا دوں.پس کیا تم گواہی دے سکتے ہو کہ یہ
سب باتیں میں نے تمہیں پہنچادیں.تب ساری قوم نے بآواز بلند تصدیق کی کہ ہم تک یہ
1013
Page 1022
سب پیغام پہنچائے گئے.تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ آسمان کی طرف اشارہ
کر کے کہا کہ اے خدا! ان باتوں کا گواہ رہ.اور پھر فرمایا کہ یہ تمام تبلیغ اس لئے مقرر کی گئی کہ
شاید آئندہ سال میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں گا.اور پھر دوسری مرتبہ تم مجھے اس جگہ نہیں پاؤ
گے.تب مدینہ میں جا کر دوسرے سال میں فوت ہو گئے اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ وَبَارِكَ وَسَلِّمُ -
( نور القرآن نمبر 1، روحانی خزائن جلد 9 صفحه 361 تا 367)
یہ سورت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب زمانہ وفات میں نازل ہوئی تھی اور اس
میں اللہ تعالیٰ زور دے کر اپنی نصرت اور تائید اور تکمیل مقاصد دین کی خبر دیتا ہے کہ اب تو
اے نبی خدا کی تسبیح کر اور تجید کر اور خدا سے مغفرت چاہ.وہ تو اب ہے.اس موقع پر مغفرت کا ذکر کرنا یہ اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ اب
کام تبلیغ ختم ہو گیا.خدا
سے دعا کر کہ اگر خدمت تبلیغ کے دقائق میں کوئی فروگذاشت ہوئی ہو تو خدا اس کو بخش دے.موسیٰ بھی تو ریت میں اپنے قصوروں کو یاد کر کے روتا ہے اور جس کو عیسائیوں نے خدا بنا رکھا
ہے کسی نے اس کو کہا کہ اے نیک استاد.تو اس نے جواب دیا کہ تو مجھے کیوں نیک کہتا ہے.نیک کوئی نہیں مگر خدا.یہی تمام اولیاء کا شعار رہا ہے.سب نے استغفار کو اپنا شعار قرار دیا
ہے.بجز شیطان کے.( براہین احمدیہ حصہ پنجم، روحانی خزائن جلد 21 صفحه 271)
اس میں اس امر کی طرف صریح اشارہ ہے کہ آپ اس وقت دنیا میں آئے جب دین اللہ
کو کوئی جانتا بھی نہ تھا اور عالمگیر تاریکی چھائی ہوئی تھی.اور گئے اُس وقت کہ جبکہ اس نظارہ کو
دیکھ لیا کہ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللهِ أَفْوَاجًا جب تک اس کو پورا نہ کر لیا نہ تھکے نہ ماندہ ہوئے.مخالفوں کی مخالفتیں، اعداء کی سازشیں اور منصوبے، قتل کرنے کے مشورے، قوم کی تکلیفیں
آپ کے حوصلہ اور ہمت کے سامنے سب پیچ اور بیکار تھیں اور کوئی ایسی چیز نہ تھی جو اپنے کام
سے ایک لمحہ کے لئے بھی روک سکتی.اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس وقت تک زندہ رکھا جب تک
کہ آپ نے وہ کام نہ کر لیا جس کے واسطے آئے.یہ بھی ایک سر" ہے کہ خدا کی طرف سے آنے
1014
Page 1023
والے جھوٹوں کی طرح نہیں آتے.الحکم جلد 5 نمبر 2 مورخہ 17 جنوری 1901 ، صفحہ 3)
دیکھو اللہ تعالیٰ نے بعض کا نام سابق مہاجر اور انصار رکھا ہے اور ان کو رضى اللهُ عَنْهُم
وَرَضُوا عَنْہ میں داخل کیا ہے.یہ وہ لوگ تھے جو سب سے پہلے ایمان لائے اور جو بعد میں
ایمان لائے ان کا نام صرف ناس رکھا ہے جیسا فرمایا إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَ الْفَتْحُ وَرَأَيْتَ
النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللهِ أَفَوَاجًا.یہ لوگ جو اسلام میں داخل ہوئے اگر چہ وہ مسلمان تھے
مگر ان کو مراتب نہیں ملے جو پہلے لوگوں کو دئیے گئے اور پھر مہاجرین کی عزت سب سے زیادہ
تھی کیونکہ وہ لوگ اس وقت ایمان لائے جب ان کو کچھ معلوم نہ تھا کہ کامیابی ہوگی یا نہیں بلکہ
ہر طرف سے مصائب اور مشکلات کا ایک طوفان آیا ہوا تھا اور کفر کا ایک دریا بہتا تھا.خاص
مکہ میں مخالفت کی آگ بھڑک رہی تھی اور مسلمان ہونے والوں کو سخت اذیتیں اور تکلیفیں دی
جاتی تھیں مگر انہوں نے ایسے وقت میں قبول کیا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بڑی
بڑی تعریفیں کیں اور بڑے بڑے انعامات اور فضلوں کا وارث ان کو بنایا.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا اور پھر وہاں سے رخصت ہونا قطعی دلیل آپ کی
نبوت پر ہے.آئے آپ اس وقت جبکہ زمانہ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ( الروم (42)
کا مصداق تھا اور ضرورت ایک نبی کی تھی.ضرورت پر آنا بھی ایک دلیل ہے اور آپ اس وقت
دنیا سے رخصت ہوئے جب إِذَا جَاءَ نَصْرُ الله کا آوازہ دیا گیا.اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا
ہے کہ آپ کس قدر عظیم الشان کامیابی کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے.تم خود ہی سوچو اور مکہ کے اس انقلاب کو دیکھو کہ جہاں بت پرستی کا اس قدر چر چا تھا کہ ہر
ایک گھر میں بت رکھا ہوا تھا.آپ کی زندگی ہی میں سارا مکہ مسلمان ہو گیا اور ان بتوں کے
پجاریوں ہی نے ان کو توڑا اور ان کی مذمت کی.یہ حیرت
انگیز کامیابی ، یہ عظیم الشان انقلاب
کسی نبی کی زندگی میں نظر نہیں آتا جو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا.یہ کامیابی
آپ کی اعلیٰ درجہ کی قوت قدسی اور اللہ تعالیٰ سے شدید تعلقات کا نتیجہ تھا.ایک وقت وہ تھا کہ
1015
Page 1024
آپ مکہ کی گلیوں میں تنہا پھرا کرتے تھے اور کوئی آپ کی بات نہ سنتا تھا اور پھر ایک وقت وہ
تھا کہ جب آپ کے انقطاع کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یاد دلایا إِذَا جَاءَ نَصْرُ الله
وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللهِ أَفْوَاجًا.آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا
که فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہوتے ہیں.جب یہ آیت اتری تو آپ نے فرمایا کہ
اس سے وفات کی بُو آتی ہے کیونکہ وہ کام جو میں چاہتا تھا وہ تو ہو گیا ہے اور اصل قاعدہ یہی ہے
کہ انبیاء علیہم السلام اسی وقت تک دنیا میں رہتے ہیں جب تک وہ کام جس کے لئے وہ بھیجے
جاتے ہیں نہ ہولے.جب وہ کام ہو چکتا ہے تو ان کی رحلت کا زمانہ آجاتا ہے جیسے بندوبست
والوں کا جب کام ختم ہو جاتا ہے تو وہ اس ضلع سے رخصت ہو جاتے ہیں.حضرت خلیفہ المسیح الاول رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:
الحکم جلد 8 نمبر 5 مورخہ 10 فروری 1904 صفحہ3)
یہ سورۃ مدنی ہے.یعنی مدینہ منورہ میں نازل ہوئی تھی.اس میں بسم اللہ شریف کے
بعد تین آیتیں ہیں اور انیس کلمے اور اُناسی حروف ہیں.ا اذا کے معنے ہیں.جب کہ.جب یہ لفظ ماضی پر آوے تو معنے استقبال کے دیتا ہے.اس واسطے إِذا جَاءَ کے معنے یہ بھی کئے گئے ہیں کہ جب آوے گی کیونکہ یہ سورۃ بطور ایک
پیشگوئی کے نازل ہوئی تھی کہ اس وقت تو اسلام تنگی اور تکالیف کی حالت میں ہے اور سب صحابہ
مہاجرین کے دل میں یہ خیال ہے کہ وہ اپنے وطنوں میں سے نکالے گئے اور ان کی تعداد قلیل
ہے اور ان کے دشمن شہر مکہ میں آرام سے ہیں.اور اُن پر ہنسی کرتے ہیں.اور طعن کرتے ہیں
کہ تم لوگوں نے اسلام میں داخل ہو کر کیا فائدہ حاصل کر لیا.دیکھو ہم نے تم کو شہر مکہ سے بھی
نکال دیا ہے.لیکن عنقریب وہ وقت آتا ہے کہ ان کی ساری شیخی کرکری ہو جاوے گی اور ان
کے متکبر سب ہلاک ہو جائیں گے.اور ملکہ کا با عظمت گھر بتوں سے پاک کیا جاوے گا اور اس
کے مناروں پر لا إلهَ إِلَّا اللہ کا نعرہ بلند کیا جاوے گا اور کمزور اور ناواقف لوگ جو اس وقت
1016
Page 1025
به سبب حجاب کے دینِ الہی میں داخل نہیں ہیں.اُن کے واسطے وقت آجائے گا کہ تمام روکیں
دور ہو کر وہ ایک سیلاب کی طرح اسلام کی طرف دوڑ پڑیں گے اور فوج در فوج لوگ اسلام
میں داخل ہونے لگ جائیں گے.اگر اذا جاء کے معنے استقبال کے نہ لئے جاویں اور اس کے یہ معنے کئے جاویں کہ
” جب فتح ونصرت الہی آگئی تب بھی یہ درست ہے.خدا تعالیٰ کی طرف سے بذریعہ وحی کے جو
پیشگوئیاں نازل ہوتی ہیں اور ان میں خدا اپنے بندے کی نصرت اور فتح کی خوشخبری دیتا ہے.چونکہ وہ بات یقینی ہوتی ہے اور ضرور ہو جانے والی ہے.کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا ہے اور
آسمان پر مقدر ہو چکا ہے کہ یہ کام اس طرح سے ہو گا.اس واسطے اس کو ایسے الفاظ میں بیان کیا
جاتا ہے کہ گویا یہ کام ہو گیا ہے.کیونکہ کوئی کام زمین پر نہیں ہوسکتا جب تک کہ پہلے آسمان پر
نہ ہو لے.اس کی مثال دنیوی محاورات میں بھی موجود ہے.جب کسی کو یقین ہو جاوے کہ اس
مقدمہ میں تمام امور میری مرضی کے مطابق طے ہو جائیں گے اور میں ضرور فتح پالوں
گا تو وہ کہتا
ہے کہ بس میں نے مقدمہ فتح کر لیا.حالانکہ ہنوز مقدمہ زیر بحث ہوتا ہے اور عدالت نے
فیصلہ نہیں سنایا ہوتا.لیکن بہ سبب یقین کے وہ ایسا ہی کہتا ہے کہ مقدمہ فتح ہو گیا.حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ جب خدا تعالیٰ کی طرف سے نبی
رسول دنیا کی طرف مبعوث ہوتا ہے تو اس کا ساتھ دینے والے لوگ تین قسم کے ہوتے ہیں.اول اور
سب سے اعلیٰ طبقہ کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو کسی معجزہ ،نشان، کرامت یا خارق عادت کے دیکھنے
کے محتاج نہیں ہوتے.وہ اس نبی کی شکل دیکھتے ہی اور اس کا دعویٰ سنتے ہی اُمَنَّا وَصَدِّقْنَا کہ اٹھتے
ہیں.ان کو نبی کے ساتھ ایک ازلی مناسبت حاصل ہوتی ہے اور وہ فورا اس پر ایمان لاتے ہیں جیسا
کہ حضرت صدیق اکبر ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے.یہ اعلیٰ طبقہ کے آدمیوں کا نمونہ ہے.اس سے کم درجہ کے لوگ وہ ہیں کہ جو کچھ تھوڑا بہت دلائل سننے اور نشان دیکھنے کے بعد
ایمان لے آتے ہیں اور مخالفت کی طرف نہیں دوڑتے اور رفتہ رفتہ محبت اور اخلاص میں بہت
ترقی کر جاتے ہیں.1017
Page 1026
اس کے بعد تیسرے درجہ کے لوگ وہ ہیں کہ جب خدا تعالیٰ کے قہری عذاب نازل ہوتے
ہیں اور ہر طرف سے فتوحات اور نصرت کے نشانات نمودار ہوتے ہیں ، تو ان کے واسطے سوائے
اس کے چارہ نہیں ہوتا کہ وہ بھی مومنوں کے درمیان شامل ہو جائیں.اوّل اور دوم درجہ کے لوگوں کی خدا تعالیٰ نے بہت تعریف کی ہے.اور ان کو رضی اللہ
عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ (المائده 120) کا خطاب دیا ہے.مگر تیسرے طبقہ کے لوگوں کا ذکر
قرآن شریف میں صرف اتنا ہے کہ رآیت النَّاس تو نے لوگوں کو دیکھا ہے.کیونکہ وہ عوام
ہیں.خواص میں ان کا ذکر نہیں.پھر بھی خوش قسمت ہیں کہ قرآن شریف میں ان کی طرف
اشارہ کر کے فرمایا گیا کہ وہ دین اللہ میں داخل ہونے والے لوگ ہیں.پہلے تو کوئی ایک آدھ مسلمان ہوتا تھا جبکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف فرما
تھے.بعد میں جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں سکونت اختیار کی تو زیادہ تعداد ہونے لگی.لیکن
پھر بھی ترقی زور کے ساتھ نہ تھی.یہاں تک کہ جب مکہ فتح ہو گیا تو گروہوں کے گروہ اور جماعتوں
کی جماعتیں دین الہی میں داخل ہونے لگیں.غفر کے معنے ہیں ڈھانکنا.دبانا.تمام انبیاء خدا تعالیٰ سے مغفرت مانگا کرتے تھے
اور مغفرت مانگنے کے یہ معنی ہیں کہ انسان چونکہ کمزور ہے اس کو معلوم نہیں کہ کونسا کام اس
کے واسطے بہتری کا ہے اور کون سا نقصان کا کام ہے اور تکلیف کا راستہ ہے.پس مغفرت
ایک دعا ہے کہ انسان اپنے خدا سے یہ دعا مانگتا ہے کہ وہ اس کے واسطے نیکی کے راہ پر چلنے
کے اسباب مہیا کرے جن سے وہ بدی سے بچا رہے اور کسی طرح کے حرج اور تکلیف میں
پڑنے سے محفوظ رہے.خدا تعالیٰ کے انعام کے حاصل کرنے کے واسطے مغفرت کا طلب کرنا
نہایت ضروری ہے.اس سورۃ شریف کا ایک نام تو النصر ہے کیونکہ اس میں ایک نصرت کی بشارت ہے
اور اس کا نام فتح بھی ہے.کیونکہ ایک عظیم الشان فتح کی اس میں پیشگوئی درج ہے جس سے
اسلامی سلطنت اور فتوحات کی بنیاد رکھی گئی تھی.یعنی فتح مگہ.ان کے علاوہ ایک نام اس
1018
Page 1027
سورۃ کا سورۃ تودیع بھی ہے.کیونکہ جب یہ سورۃ نازل ہوئی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا.کہ نُعِیتُ إلی اور آپ نے سمجھ لیا ہمارا کام تکمیل کو پہنچ چکا ہے.اور اب وقت آ گیا ہے
کہ ہم اپنے خدا کے پاس چلے جاویں.حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب یہ سورۃ نازل ہوئی اور آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے
کہ جو آپ کا کام تھا وہ پورا ہو گیا ہے اور اب آپ کو اس دار فانی کو چھوڑنے کا وقت قریب آ
گیا ہے تو آپ نے ظاہر فرمایا کہ اب میں عالم باقی میں انتقال کروں گا.اس بات کوشن کر
جناب فاطمہ رضی اللہ عنہا رونے لگیں.آپ نے فرمایا تم کیوں روتی ہو؟ اہل بیت میں سے سب
سے پہلے مجھ سے تم ہی ملو گی! یہ سن کر وہ مسکرانے لگیں.اس میں بھی ایک پیشگوئی تھی.چنانچہ اس
کے بعد جلد آ نحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے اور آپ کے بعد اہل بیت میں سب سے اول
جس نے وفات پائی وہ حضرت فاطمہ ہی تھیں.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا یہ
عجیب نمونہ ہے کہ حضرت فاطمہ کو آنحضرت کی وفات کی خبر نے رُلا دیا.لیکن پھر اپنی وفات کی
خبر نے اس واسطے ہنسایا کہ اس میں آنحضرت کے ساتھ دوسرے عالم میں ملاقات کی جلد صورت
پیدا ہوگئی تھی.اپنے مرنے کا خوف نہیں اور آنحضرت کے ساتھ ملاقات کی خوشی غالب ہے.اخبار بدر قادیان 21 /نومبر 1912ء)
سورۃ شریف میں إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ میں لفظ فتح سے مراد فتح مکہ ہے.حمد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ اس سورۃ شریف کے نزول کے بعد
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم رکوع وسجود میں یہ دعا بہت پڑھتے تھے.سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ -
اسْتَغْفِرُ اللهَ رَبِّي مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ.اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ اس کے
بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے بیٹھتے ، آتے جاتے ، ہر وقت سُبحان
اللہ و بحمدہ کہتے اور
فرماتے کہ مجھے ایسا کہنے کے واسطے حکم دیا گیا ہے.اور اس سورۃ کو پڑھتے.اس میں اول تسبیح کا حکم ہے پھر تحمید کا اور پھر استغفار.اس ترتیب میں یہ حکمت معلوم ہوتی
ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات دو قسم پر ہیں.ایک صفات سلبیہ اور دوم صفات ثبوتیہ.1019
Page 1028
صفات سلبیہ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے تمام نقائص سے پاک اور منزہ ہ ہونا اور اعلیٰ و برتر ہونا ظاہر
کرتی ہیں.سلبیہ کے معنے سلب کرنے والی کھینچنے والی.اور صفات ثبوتیہ وہ ہیں جو اللہ
تعالیٰ کے اکرام اور عزت اور بلندی کا اظہار کرتی ہیں.اس ترتیب میں صفات سلمیہ کا پہلے ذکر
کیا گیا ہے اور صفات ثبوتیہ کو ان کے بعد لیا گیا ہے.تسبیح اللہ تعالی کی جلالی صفات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ وہ تمام بدیوں سے منزہ ہ اور
بے عیب اور پاک ذات ہے.تم بھی اس کی تسبیح کرو.یعنی اس کا مقدس اور پاک ہونا بیان
کرو.اور اس کی تحمید کرو کہ وہ تمام حمد کا مالک ہے اور سچی تعریف اسی کے لائق ہے.اس
کے بعد استغفار ہے جو کہ انسان کو اپنے قصور نفس اور کمزوری کی طرف تو حجہ دلاتا ہے اور خدا
تعالیٰ کی بخشش کی طرف انسان کو کھینچتا ہے کہ اس کے سوائے انسان کا گزارہ نہیں اور انسان
کے نفس کو کامل کرنے والی وہی ذات پاک ہے جس کے ساتھ بچے اور خالص تعلق کے ذریعہ
انسان بدیوں سے نجات پاسکتا ہے اور نیکیوں کے حصول کی اس کو توفیق ملتی ہے.حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ سب سے آخر جو سورۃ به تمام و کمال اور پوری اتری
وہ یہی سورۃ النصر ہے.اس کے بعد کوئی پوری سورۃ آ نحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں
ہوئی.ایک حدیث میں آیا ہے کہ یہ سورۃ ربع قرآن ہے.یعنی قرآن شریف کی چوتھائی
کے برابر ہے.یہ فضیلت بلحاظ اس شاندار پیشگوئی کے معلوم ہوتی ہے جس پر وہ مشتمل ہے.اور بلحاظ ان احکام تسبیح اور تحمید اور استغفار کے ہے جو کہ انسان کو اپنے کمال تک پہنچانے کے
واسطے کمال درجہ کے ہتھیار ہیں.اسی سورۃ شریف نے کفار مکہ کو با وجود ایسی سخت بغاوتوں اور
سرکشیوں کے اور اذیت رسانیوں کے فتح مکہ کے وقت ہر طرح کے عذاب سے بچا لیا.اور
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خُلق عظیم کے ساتھ سب کو معاف کر دیا اور
فرما يالَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ.بلکہ ان کے گناہوں کے واسطے خدا تعالیٰ کے حضور میں
معافی چاہی.کیونکہ آستغْفِرُ اللہ کا لفظ اسی امر کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آپ خدا تعالیٰ کے
حضور میں گناہگاروں کے واسطے شفاعت کریں اور ان کو عذاب میں گرنے سے بچاویں.1020
Page 1029
یہ اللہ تعالیٰ کی فتح و نصرت کا وعدہ اور قوموں کے فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے کی
پیشگوئی جو اس سورۃ شریف میں کی گئی ہے.اگر چہ اس کے پورا ہونے کا ابتدا آ نحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کے زمانہ میں ہوا.تا ہم چونکہ مذہب اسلام ہمیشہ کے واسطے ہے.اس واسطے ظلمی طور
پر جب کبھی ضرورت ہو یہ وعدہ پورا ہوتا ہے.چنانچہ اس زمانہ میں بھی جبکہ اسلام بہت ضعیف
ہے خدا تعالیٰ نے اپنے ایک فرستادہ کے ذریعہ سے یہ خوشخبری دوبارہ سنائی ہے کہ اس کی طرف
سے اسلام کے واسطے فتح ونصرت کا وقت پھر آ گیا ہے اور لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہوں
گے اور پھر اسلامیوں میں وہی روحانیت پھونکی جائے گی.مبارک ہیں وہ جو تکبر نہ کریں اور خدا
کے کام کی عزت کریں تا کہ ان کے واسطے بھی عزت ہو.اے خدا ہمارے گناہوں کو بخش اور
اپنے وعدوں کو پورا کر کہ تو سچے وعدوں والا ہے.اسلام کی عزت کو دنیا میں قائم کر دے اور اسلام
کے دشمنوں کو ذلیل اور پست اور بلاک کر دے خواہ وہ اندرونی ہوں یا بیرونی.کیونکہ اب تیری
قدرت نمائی کا وقت ہے اور تو بڑی طاقتوں والا خدا ہے.آمین ثم آمین.اس سورہ شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انجام کو ظاہر کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا
ہے فَسَبِّحْ بحمد ربك.اللہ کی تسبیح کرو، اس کی ستائش اور حمد کرو، اور اس سے حفاظت طلب
کرو.استغفار یا حفاظتِ الہی طلب کرنا ایک عظیم الشان سر" ہے.انسان کی عقل تمام ذاتِ
عالم کی محیط نہیں ہوسکتی.اگر وہ موجود ضروریات کو سمجھ بھی لے تو آئندہ کے لئے کوئی فتوی نہیں
دے سکتی.اس وقت ہم کپڑے پہنے کھڑے ہیں.لیکن اگر اللہ تعالیٰ ہی کی حفاظت اور فضل کے
نیچے نہ ہوں اور محرقہ ہو جاوے تو یہ کپڑے جو اس وقت آرام دہ اور خوش آئندہ معلوم ہوتے ہیں
ناگوار خاطر ہو کر موذی اور مخالف طبع ہو جاویں اور وبالِ جان
سمجھ کر ان کو اتار دیا جاوے.پس
انسان کے علم کی تو یہ حد اور غایت ہے.ایک وقت ایک چیز کو ضروری سمجھتا ہے اور دوسرے
وقت اسے غیر ضروری قرار دیتا ہے.اگر اسے یہ علم ہو کہ سال کے بعد اسے کیا ضرورت ہوگی؟
مرنے کے بعد کیا ضرورتیں پیش آئیں گی؟ تو البتہ کہ سکتے ہیں کہ وہ بہت کچھ انتظام کرے.لیکن جب قدم قدم پر لاعلمی کے باعث ٹھوکریں کھاتا ہے.پھر حفاظتِ الہی کی ضرورت نہ سمجھنا
1021
Page 1030
کیسی نادانی اور حماقت ہے.یہ صرف علم ہی تک بات محدود نہیں رہتی.دوسرا مرحلہ
تصر فاتِ عالم کا ہے.وہ اس کو مطلق نہیں.ایک ذرہ پر اُسے تصرف و اختیار نہیں.غرض
ایک بے علمی اور بے بسی تو ساتھ ہے.پھر بد عملیاں ظلمت کا موجب ہو جاتی ہیں.انسان جب
اولاً گناہ کرتا ہے تو ابتدا میں دلیر نہیں ہوتا ہے.پھر وہ امر بڑھ جاتا ہے.اور دین کہلاتا ہے
اس کے بعد مہر لگ جاتی ہے.یہ چھاپا مضبوط ہو جاتا ہے.قفل لگ جاتا ہے.پھر یہاں تک
نوبت پہنچتی ہے کہ بدی سے پیار اور نیکی سے نفرت کرتا ہے.خیر کی تحریک ہی قلب سے اُٹھ
جاتی ہے.اس کا ظہور ایسا ہوتا ہے کہ خیر و برکت والی جانوں سے نفرت ہو جاتی ہے.یا توان
کے حضور آنے ہی کا موقعہ نہیں ملتا یا موقعہ تو ملتا ہے لیکن انتفاع کی توفیق نہیں پاتا.رفتہ رفتہ
اللہ سے بعد ، ملائکہ سے دُوری اور پھر وہ لوگ جن کا تعلق ملائکہ سے ہوتا ہے اُن سے بعد ہو کر
کٹ جاتا ہے.اس لئے ہر ایک عقلمند کا فرض ہے کہ وہ تو بہ کرے اور غور کرے.ماخوذ از حقائق الفرقان زیر تفسیر سورة النصر )
حضرت خلیفہ امسیح الثانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:
روایات سے ثابت ہے کہ یہ سورۃ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے قریب
نازل ہوئی تھی پس در حقیقت إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَ الْفَتحُ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
وفات کی پیشگوئی کی گئی ہے.یہ بتانے کے لئے کہ یہ فتوحات جو محمد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کو حاصل ہوئی ہیں ان کا سلسلہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تک محدود نہیں بلکہ آئندہ
بھی ان کا سلسلہ جاری رہے گا.چنانچہ حضرت ابوبکرؓ کے زمانہ میں قیصر روما سے جنگ چھڑی
اور پھر حضرت عمرؓ کے زمانہ میں کیسری اور قیصر کو مکمل طور پر شکست ہوگئی.پس إِذَا جَاءَ نَصْرُ الله
وَالْفَتْحُ میں ان فتوحات کا ذکر تھا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر اور
حضرت عمرؓ اور حضرت عثمان کے زمانہ میں ہونے والی تھیں.رض
پس سورۃ نصر میں اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ آپ
1022
Page 1031
گھبرائیں نہیں، کیونکہ اسلام کی فتوحات کا سلسلہ بند نہیں ہوگا بلکہ جاری رہے گا.اور اسلام دنیا پر
غالب آ جائے گا.لیکن اس کے ساتھ ہی یہ حکم بھی دیا کہ چونکہ آئندہ اسلام میں لوگ گروہ در گروہ
داخل ہونے والے ہیں.اس لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان مسلمانوں کے لئے دعا کرنی
چاہئے تا ان کی صحیح تربیت ہو کر اسلام میں کسی خرابی کی بنیاد نہ پڑے اور اگر کوئی خرابی پیدا ہو تو اللہ
اس کی اصلاح کا سامان پیدا کرد -
اس سورۃ کا پہلی سورۃ سے یہ تعلق ہے کہ سورۃ کافرون میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اور آپ کے ساتھیوں کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ اعلان کر دیں کہ وہ اسلام کے منکروں کے معبودوں
کی عبادت نہیں کر سکتے اور نہ ان کی عبادت کے طریقوں کو اختیار کر سکتے ہیں جن کو اسلام کے
منکرین اختیار کئے ہوئے ہیں.اسی طرح کفار کے متعلق یہ بیان تھا کہ وہ اپنے عبادت کے
طریقوں کو چھوڑنے والے نہیں.اس کے بعد سورۃ نصر کو رکھ کر اس لطیف مضمون کو بیان فرمایا
ہے کہ تھوڑے عرصہ میں اسلام کو عظیم الشان فتوحات حاصل ہونے والی ہیں.اور جب
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جب ان کے اتباع عملی طور پر یہ دیکھ لیں گے کہ جو طریق انہوں
نے اختیار کیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کی تائید کی ہے تو کس طرح ممکن ہوسکتا ہے کہ وہ اس طریق
کو اختیار کریں جس کے ساتھ خدا نہیں، اور پھر شکست خوردہ طریق بھی ہے.اسی طرح جب
کفار دیکھ لیں گے کہ ان کی جماعت ٹوٹ گئی اور تمام کار آمدلوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
سے جاملے تو وہ بھی خواہ فطرتا شرک کے حق میں ہوں مگر ان کی ضمیر ان کو مجبور کر کے اسلام میں
داخل کردے گی.پس گو وہ ظاہر میں مسلمانوں کا طریق عبادت اختیار کریں گے مگر در حقیقت یہ
خدائی معجزہ کے ماتحت ہوگا.ان کی اپنی مرضی سے نہیں.اگر اپنی مرضی پر انہیں رہنے دیا جاتا،
تو اپنے آباؤ اجداد کی تعلیم کے مطابق کبھی وہ اسلامی عبادات اختیار نہ کرتے.اسی طرح سورۃ نصر کا سورۃ کافرون کی آخری آیات کے ساتھ بھی ایک تعلق ہے اور وہ
یہ کہ سورۃ کافرون کی آخری آیات میں یہ کہا گیا تھا.لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ.کہ اے کا فرو!
1023
Page 1032
تمہارے نزدیک غلبہ کا مفہوم یہ ہے کہ جب کوئی تمہارے مذہب سے ذرا ادھر اُدھر ہوا.تم
لٹھ لے کر کھڑے ہو گئے.اس کو مارا پیٹا اور اس کی جان لینے کے درپے ہو گئے.اور اس کو
جبر و اکراہ سے اپنے بتوں اور معبودوں کی طرف لانے کی کوشش کی اور ہر طرح کا ظلم روا
سمجھا.لیکن اسلام ایسے غلبہ کو غلبہ نہیں بلکہ شکست سمجھتا ہے.اور اسلام کے نزدیک غلبہ کا
مفہوم یہ ہے کہ ایسے دلائل پیش کئے جائیں جو دل اور دماغ پر قابو پالیں اور ایک ہوشمند انسان
ان دلائل کے سامنے ہتھیار ڈال دے اور ہمیشہ کے لئے غلام ہو جائے.اور یہ کہ مذہب کے
بارہ میں جبر سے کام لینے کی بجائے دلائل و براہین سے کام لینا چاہئے.اور مذہب کے اختیار
کرنے میں پوری آزادی ہونی چاہئے.اے کا فرو! تم نے اپنے ہتھیار کو استعمال کیا اور
مسلمانوں نے اپنے ہتھیار کو استعمال کیا.اب تھوڑے دنوں میں نتیجہ نکل آئے گا کہ باوجود
تمہارے پورے جبر کے تمہاری ساری قوم ٹوٹ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ
گرے گی.اور یہ ظاہر ہے کہ جب تمہاری قوم مسلمان ہو جائے گی تو مسلمانوں کو تمہارے
ساتھ شامل ہونے کی ضرورت نہیں رہے گی.پس جو دعویٰ سورۃ کافرون کی آخری آیت میں کیا
گیا تھا وہ ثابت ہو جائے گا کہ غلبہ کے متعلق کفار کا نظریہ اور ہے اور مسلمانوں کا اور ہے.لیکن سچا نظریہ یہی ہے جو مسلمانوں کا ہے کہ وہی جیتے گا جو دلیل سے کام لے گا اور تلوار اور سونٹا
ناکام رہیں گے.یہ سورۃ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے صرف سٹر دن پہلے نازل ہوئی تھی اور
یہ کہ اس سورۃ کے نازل ہونے کے ساتھ ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم بھی دے دیا گیا
تھا کہ اب آپ کی وفات کا وقت قریب ہے.إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ
اس آیت کے متعلق یہ امر بھی ذکر کے قابل ہے کہ اس میں الفتحُ پر ال داخل کیا گیا
ہے.اور عربی زبان میں جب کبھی لفظ پر ال داخل کیا جائے تو اس کے معنے ہوتے ہیں کہ
1024
Page 1033
مخاطب اس امر کو جانتا ہے.جیسے رجُل کے معنے ہوں گے کوئی آدمی.اور جب اس پر ال
داخل کر دیں اور کہیں الرجل تو اس کے معنے ہوں گے وہ خاص آدمی جس کو متکلم اور مخاطب
دونوں جانتے ہیں.پس آیت إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَ الْفَتْح میں الْفَتْحُ پر ال داخل کر کے یہ کہا
گیا ہے کہ یہ فتح جس کے وعدے دیے جا رہے ہیں ایسی ہے کہ جس کو محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں اور یہ بات درست ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کو یہ نظارے کشف
میں دکھا دیتے تھے.ني الفشخ میں ال کمال کے معنوں میں بھی ہو سکتا ہے اور معنے یہ ہوں گے کہ جب کامل فتح
آ جائے گی.وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللهِ أَفْوَاجًا.یعنی جب اللہ تعالیٰ کی نصرت اور موعود
فتح آ جائے گی اور تولوگوں کو اللہ کے دین میں گروہ در گروہ داخل ہوتے دیکھ لے گا.یہاں یہ
سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو آپ نے فوج در فوج
لوگوں کو اسلام میں داخل ہوتے کس طرح دیکھا.اس کے متعلق یہ امر یا درکھنا چاہئے کہ...رؤیت کا لفظ صرف آنکھ سے دیکھنے پر استعمال نہیں ہوتا.بلکہ یہ دل سے کسی چیز کو پالینے یا اس
کا علم حاصل کر لینے پر بھی بولا جاتا ہے.اور اسی طرح کشفاً کسی چیز کو دیکھنے پر بھی استعمال ہو
سکتا ہے.نیز عربی محاورہ میں یقینی اور قطعی خبر کو بھی دیکھنے سے تعبیر کیا جاتا ہے.چنانچہ قرآن
کریم میں آتا ہے اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْبِ الْفِيلِ (سورة الفيل) یعنی اے محمد
رسول اللہ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اصحاب الفیل کے ساتھ تیرے رب نے کیا کیا.حالانکہ یہ
واقعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے بھی ایک سال پہلے ہوا تھا تو گویا یہاں پختہ علم
کے لئے رایت کا لفظ استعمال ہوا ہے.پس رآیت النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ
اللهِ أَفْوَاجًا کے
معنے یہ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور اس کی فتوحات آجانے کے بعد جس طرح لوگوں نے
جوق در جوق اسلام میں داخل ہوتا ہے یہ نظارہ اللہ تعالیٰ تجھ کو کشفاً دکھا دے گا.یا اس کے آثار
پیدا کر کے یہ یقین تیرے دل میں پیدا کر دے گا کہ اسلام غالب ہو کر رہے گا.1025
Page 1034
فَسَيْحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ
سبیح کے معنے اللہ تعالیٰ کی ذات کو تمام عیوب اور نقائص سے مبرا قرار دینے کے
ہوتے ہیں اور حمد کے معنے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں تمام خوبیوں کے ہونے کا اقرار
کیا جائے.حمد اس آیت میں لفظ رب استعمال فرمایا.یعنی یہ کہا ہے کہ اپنے رب کی حمد کرو.یہ نہیں کہا
کہ اللہ کی حمد کرو.رب کے معنوں کے اندر یہ مفہوم پایا جاتا ہے کہ اونی حالت سے ترقی دیتے
دیتے کمال تک پہنچانا.گویا رب کا لفظ اس آیت میں استعمال کرنے میں یہ حکمت ہے کہ تا یہ
بتایا جائے کہ اللہ تعالیٰ اس لئے حمد کا مستحق ہے کہ اس نے مسلمانوں کو ضعف کی حالت سے
اُٹھا کر ساری دُنیا کا مالک بنا دیا.پس جو کسی پر اتنا فضل کرے وہ بہر حال حمد کا مستحق ہوگا.پھر حمد کے لفظ میں یہ اشارہ بھی کیا گیا ہے کہ اے مسلمانو! فتوحات کو دیکھ کر تمہارے
اندر کبر پیدا نہ ہو.اور یہ نہ سمجھنا کہ یہ فتوحات تمہاری کیسی ذاتی قابلیتوں کی بناء پر ہیں.بلکہ یہ
سب کچھ خدا کے فضل کے ماتحت تم کو میل رہا ہے اس لئے تمہیں خدا تعالیٰ کی حمد کرتے ہوئے
اس کے آستانے پر ہمیشہ جھکے رہنا چاہئے.تا تمہارا یہ شکر ادا کرنا اللہ تعالیٰ کے مزید فضلوں کو
نازل کرنے کا موجب ہو.الغرض فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ کے الفاظ میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اے
مسلمانو! تم اعلان کر دو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدوں کے مطابق ہماری نصرت کر کے ایک
طرف اپنی ذات کو تمام الزامات سے بری ٹھہرالیا ہے اور دوسری طرف اپنی ذات کو حمد کا مستحق
قرار دے لیا ہے.استغفار کے معنے ڈھانکنے یا حفاظت کرنے کے ہیں.اور استغفار کے معنے ہیں
حفاظت کے لئے دعا یا طلب حفاظت.گویا استغفار کرنے والا شخص اللہ تعالیٰ سے دُعا کرتا ہے
کہ وہ اس کو اپنی حفاظت میں لے لے اور اس کی بشریت کی کمزوریاں ظاہر نہ ہوں.یا یہ کہ وہ
خدا تعالیٰ کی حفاظت میں اس طور پر آ جائے کہ اس سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو.1026
Page 1035
قرآن کریم نے استغفار کے معنے میں وسعت پیدا کرتے ہوئے اس کو ان معنوں میں بھی
استعمال کیا ہے کہ جو گناہ انسان سے صادر ہو چکے ہوں ان کے بدنتائج اور ان کی سزا سے بچنے
کے لئے اللہ تعالیٰ کی حفاظت طلب کی جائے.چنانچہ قرآن کریم میں یہ لفظ اس مفہوم میں
کثرت سے استعمال ہوا ہے.اور یہ ادنی لوگوں کے لئے ہے.کامل لوگوں کے لئے اس کا یہی
مفہوم ہوتا ہے کہ قوم کی اصلاح کرتے ہوئے اگر کوئی امر نظر انداز ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کا
ازالہ کر دے.سورۃ نصر کی زیر تفسیر آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوحکم دیا ہے کہ
اے ہمارے رسول ! اِسْتَغْفِرُهُ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو.اسی طرح قرآن کریم میں بعض
مقامات پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے استغفر لذنبك كے الفاظ بھی استعمال ہوئے
ہیں کہ اپنے ذنب کے لئے استغفار کرو.ایسے مقامات کو پڑھتے وقت یہ سوال ہوتا ہے کہ استغفار کا لفظ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کے لئے کن معنوں میں استعمال ہوا ہے؟ کیا ان معنوں میں کہ آپ سے کوئی گناہ سرزد ہو اتھا
اور پھر آپ کو حکم ہوا کہ آپ اس کی سزا سے بچائے جانے کی دعا کریں یا کسی اور معنے میں؟
ان آیات کو جن میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے استغفار کا لفظ استعمال ہوا ہے
حل کرنے کے لئے یہ امر اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہئے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا
کی ہدایت اور راہنمائی کے لئے آئے تھے اور اس دنیا میں اس لئے مبعوث کئے گئے تھے کہ تا
گمراہ اور بے دین لوگوں کو باخدا انسان بنائیں اور تا گنا ہوں اور بدیوں میں گرفتار شدہ انسانوں
کو پاک وصاف کریں.اور آپ کا درجہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں بیان
فرمایا ہے.قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ (آل عمران (32) اے
ہمارے رسول ! تم یہ بات لوگوں کو اچھی طرح سنا دو کہ اگر وہ خدا تعالیٰ سے محبت رکھتے ہیں تو
اُن کو چاہئے کہ وہ تیری اتباع کریں.اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اللہ تعالی کے پیارے اور محبوب
بن جائیں گے.پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت قرآن کریم میں آتا ہے لقد كان
1027
Page 1036
لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (احزاب (22) کہ اے مسلمانو! اس رسول میں تمہارے
لئے ایک نیک نمونہ ہے.اگر تم خدا کے حضور مقبول بننا چاہتے ہو اور اگر تم خدا سے تعلق پیدا کرنا
پسند کرتے ہو تو اس کا آسان طریق یہ ہے کہ اس رسول کے اقوال، افعال اور حرکات و سکنات
کی پیروی کرو.کیونکہ آپ کے اقوال و افعال خدا تعالیٰ کے اقوال و افعال ہیں جیسا کہ
قرآن کریم نے آپ کے متعلق مَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ الله رلى (انفال (18) کہہ کر
آپ کے کنکر پھینکنے کو اللہ تعالیٰ کا کنکر پھینکنا قرار دیا ہے.پھر آپ کے متعلق یہ بھی فرمایا کہ
مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى (النجم (4-5) یعنی یہ نبی اپنی خواہش سے کلام
نہیں کرتا بلکہ وہی بات کہتا ہے جو خدا تعالیٰ اس کو بذریعہ وحی حکم دیتا ہے.پس وہ شخص جس کی
اتباع سے انسان خدا سے ملتا ہی نہیں بلکہ اس کا محبوب بن جاتا ہے.اور وہ شخص جو دنیا کے
لئے ایک نمونہ تھا اور جس کے اقوال و افعال خدا کے اقوال و افعال تھے اس کا استغفار ان
معنوں میں نہیں ہو سکتا کہ اس سے کوئی گناہ سرزد ہو ا تھا اور اس نے یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس
کو اس گناہ کی سزا سے بچالے.کیونکہ یہ ظاہر بات ہے کہ اگر وہ بھی گناہ کا مرتکب ہوسکتا تھا تو
خدا تعالیٰ نے اس کی اشباع کا کیوں حکم دیا اور اُسے دُنیا کے لئے نمونہ کیوں قرار دیا؟ پس آپ
ہر ایک بدی اور گناہ سے پاک تھے.گویا آپ کا استغفار گناہوں کی سزا سے بچنے کے لئے نہ
تھا بلکہ کسی اور معنے میں تھا.ا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر وہ کون سے معنے ہیں جن کو ادا کرنے کے لئے
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے استغفار کا لفظ استعمال ہوا ہے؟
سو جاننا چاہئے کہ زیر تفسیر سورۃ کی ابتدائی دو آیات میں یہ مضمون بیان کیا گیا ہے کہ
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی مسلمانوں کی نصرت کا سلسلہ جاری رہے گا اور
فتوحات کے دروازے ان کے لئے کھول دیئے جائیں گے.اور قومیں محمد رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم سے اس طرح برکت پائیں گی جس طرح آپ کی زندگی میں لوگوں نے برکت پائی
تھی.گویا ان آیات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا یا گیا تھا کہ آئندہ زمانہ میں
1028
Page 1037
ہزاروں ہزار لوگ اسلام میں ایک وقت میں داخل ہوا کریں گے.اور یہ ظاہر ہے کہ جب کسی
قوم کو فتح حاصل ہوتی ہے اور مفتوح قوم کے ساتھ فاتح قوم کے تعلقات قائم ہوتے ہیں تو ان
میں جو بدیاں اور برائیاں ہوتی ہیں وہ فاتح قوم میں بھی آنی شروع ہو جاتی ہیں.یہی وجہ ہے کہ
فاتح قوم جن ملکوں سے گزرتی ہے ان کے عیش و عشرت کے جذبات اپنے اندر لے لیتی ہے اور
چونکہ عظیم الشان فتوحات کے بعد اس قدر آبادی کے ساتھ فاتح قوم کا تعلق ہوتا ہے جو فاتح سے
بھی تعداد میں زیادہ ہوتی ہے.اس لئے اس کو فوز اتعلیم دینا اور اپنی سطح پر لانا مشکل ہوتا ہے.اور جب فاتح قوم کے افراد مفتوح قوم میں ملتے ہیں تو بجائے اس کو اخلاقی طور پر نفع پہنچانے
کے خود اس کے بداثرات سے متأثر ہو جاتے ہیں.جس کا نتیجہ رفتہ رفتہ نہایت خطرناک ہوتا
ہے.اور در حقیقت جس وقت کوئی قوم ترقی کرتی اور کثرت سے پھیلتی ہے وہی زمانہ اس کے
تنزل اور انحطاط کا بھی ہوتا ہے.پس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان فتوحات کی خبر کو معلوم کر
کے طبعی طور پر متفکر ہو سکتے تھے.کہ ان فتوحات کے ساتھ ساتھ کہیں مسلمانوں میں انحطاط تو
شروع نہ ہو جائے گا اور وہ لوگ جو اسلام میں نئے داخل ہوں گے ان کی پوری طرح تربیت کا
کیا سامان ہوگا کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کامل استاد اور نفوس کا تزکیہ کرنے والا اور
کامل راہنما ان کو میسر نہ ہوگا.پس ان خیالات کے جواب کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اِسْتَغْفِرُهُ
کے الفاظ نازل فرمائے اور بتایا کہ اے محمد رسول اللہ ! جب تک آپ دنیا میں رہے آپ نے
اپنی ذمہ داری کو ادا کیا اور تربیت اور تزکیہ نفوس کا کام کرتے رہے.لیکن جب آپ مہمارے
پاس آ جائیں گے تو آپ کی ذمہ داری ختم ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ خود امت محمدیہ کا کفیل ہو
جائے گا.ایسی صورت میں آپ کو فکر کی کیا ضرورت ہے.ہاں آپ وہ کام کریں جو آپ کی
استطاعت میں ہے.اور وہ یہ کہ آپ دُعاؤں میں لگ جائیں اور اللہ تعالیٰ سے التجا کریں کہ وہ
نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کی حفاظت کرے اور ان کی نصرت کرتا رہے بلکہ اسلام میں نئے داخل
ہونے والوں کی بھی خود ہی تربیت کا سامان کرے اور ایسی صورت پیدا کر دے کہ تمام مسلمان
1029
Page 1038
ٹھوکر اور غلطیوں سے بچتے رہیں.اور اگر کبھی کوئی رخنہ پیدا بھی ہو تو اس کی اصلاح کا سامان
خدا تعالیٰ پیدا کرتار ہے.گویا رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات کے لئے استغفار کرنے
کا حکم نہیں دیا گیا بلکہ اپنی امت کے لوگوں کے لئے استغفار کا حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالی سے
آپ دُعا کریں کہ وہ آپ کی اُمت کی حفاظت فرمائے اور ان میں کوئی روحانی طور پر رخنہ
نہ پڑے.اور اگر کوئی خرابی پیدا ہو تو اس کی اصلاح کا سامان پیدا ہو جائے.چنانچہ روایات
سے پتہ چلتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کے مطابق دعا کرنی شروع کر دی اور
واقعات بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دُعا کو شرف قبولیت بخشا اور آپ کی وفات کے بعد
جس قدر فتنے پیدا ہوئے ان کی اصلاح کر دی گئی اور آئندہ ایسا انتظام کر دیا گیا کہ ہر فتنے کے
پیدا ہونے پر اس کی اصلاح ہو جائے.اسلام کی فتوحات کے زمانہ میں جب کثرت سے عیسائی لوگ مسلمان ہوئے تو وہ اپنے
ساتھ حیات مسیح اور مسیح کے بے گناہ ہونے اور باقی تمام انسانوں کے (جن میں محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم بھی آجاتے ہیں) خطا کار ہونے کا عقیدہ بھی لے آئے اور وہ اتنا پھیلا کہ اس
غلط فہمی کی وجہ سے عیسائیت کو اسلام پر حملہ کرنے کا موقع میل گیا اور مسلمان اسلام کو چھوڑ کر
عیسائیت میں داخل ہونے شروع ہو گئے.آخر اللہ تعالیٰ نے اس فتنے کے استیصال کے لئے
اور امت کی حفاظت کے لئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے وجود کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کے چودہ سو سال بعد کھڑا کر دیا.اور آپ کے ذریعہ اسلام کو ایسے مقام پر کھڑا کر دیا کہ کجاوہ
حالت کہ وہ اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتا تھا اور مسلمان اسلام کو چھوڑ رہے تھے.اور کجا یہ حالت پیدا
ہوگئی کہ تمام مذاہب میدان سے بھاگ گئے اور اسلام عیسائیت پر حملہ آور ہو گیا اور غیر مذاہب
کے لوگ کثرت سے اسلام میں داخل ہونے شروع ہو گئے.اور وہ دن دور نہیں جبکہ ہر شخص
اسلام کے ماڈی غلبہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا اور اسلام کا ضعف اُس کی طاقت میں
تبدیل ہو جائے گا.پس یہ سب کچھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استغفار اور دعا کا نتیجہ ہے.1030
Page 1039
خلاصہ کلام یہ کہ سورۃ نصر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفرہ کا حکم دینے سے
مراد یہ ہے کہ آپ دُعا کریں کہ فتوحات کے نتیجے میں جو خرابیاں اُمت محمدیہ میں پیدا ہوسکتی ہیں
اللہ تعالیٰ خود ان کی اصلاح کا انتظام فرمادے.إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا
تاب کے معنے ہوتے ہیں فضل کے ساتھ رجوع کیا.اور تو اب مبالغہ کا صیغہ ہے اس
لئے اس کے معنے ہوں گے بار بار فضل کے ساتھ رجوع کرنے والا.گویا اس حصہ آیت میں
اس مضمون کو ادا کیا گیا ہے کہ اے محمد رسول اللہ ! اگر آپ دُعاؤں میں لگ جائیں گے تو
اللہ تعالیٰ آپ کی دُعاؤں کو ضرور سُنے گا.اور اپنے فضل کے ساتھ آپ کی قوم پر بار بار رجوع
کرے گا.نبوت، صدّیقیت، شہیدیت اور صالحیت چار روحانی انعام ہیں جن کو قرآن کریم نے
بیان فرمایا ہے اور بتایا ہے کہ ان انعاموں کا ملنا خدا تعالیٰ کے فضل پر منحصر ہے.چنانچہ اللہ
تعالیٰ فرماتا ہے.وَمَنْ يُطِعِ الله وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ
النَّبِيِّن والصَّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاء وَالصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا.ذلِكَ الْفَضْلُ مِنَ
اللهِ وَ كَفَى بِاللهِ عَلِیما (النساء 71-70) یعنی جو اللہ اور رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کی کامل
اطاعت کرے گا تو وہ ان لوگوں کے زمرہ میں شامل ہو جائے گا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا.یعنی نبی، صدیق ، شہید اور صالح.اور ان مقامات کا ملنا اللہ تعالی کے فضل سے ہوتا ہے اور
اللہ تعالیٰ بوجہ علیم ہونے کے پوری طرح جانتا ہے کہ کون ان فضلوں کا مورد ہونے کا اہل ہے.پس إِنَّهُ كَانَ تو ابا کے الفاظ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی گئی ہے کہ جب
بھی آپ کی قوم کو حفاظت کی ضرورت ہوگی ، جب بھی کسی اصلاح کی ضرورت ہوگی اللہ تعالیٰ
اس کی حفاظت اور اصلاح کے ذرائع پیدا کر دے گا.اور اس خرابی کے مناسب حال شخص پیدا
کر دے گا.چنانچہ واقعات بتاتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائنی گئی اور امت
1031
Page 1040
میں جب بھی کوئی خرابی پیدا ہوئی تو اس کی اصلاح کے لئے اللہ تعالیٰ نے اس کے
مناسب حال شخص کھڑا کر دیا.روایت میں آتا ہے کہ سورۃ نصر کے نزول پر اللہ تعالیٰ کے حکم سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ
وَاسْتَغْفِرْ کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دُعائیہ کلمات اُٹھتے بیٹھتے چلتے
پھرتے پڑھا کرتے تھے کہ سُبْحَانَكَ اللهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ (در منثور)
یعنی اے اللہ ! میں تیری تسبیح کرتا ہوں اور تیری ذات میں سب خوبیوں کے ہونے کا اقرار کرتا ہوں
اور تجھ سے بشری کمزوری پر پردہ پوشی چاہتا ہوں اور تیری طرف ہی رجوع کرتا ہوں.حضرت ام سلمہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال
کیا کہ یا رسول اللہ آپ یہ دعا بار بار کیوں پڑھتے ہیں؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اسی قسم کی دُعا کرنے کا ارشاد فرمایا ہے اور پھر سورۃ نصر کی آیات
پڑھیں.بہر حال اس روایت سے ثابت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے
حکم کے مطابق اپنی امت کے لئے کثرت سے دعائیں کیں تا آپ کی اُمت راہ راست پر قائم
رہے اور جب کبھی اس میں کوئی خرابی پیدا ہو تو اللہ تعالیٰ ایسے اشخاص کو کھڑا کر دے جو اس
خرابی کو دور کر دیں اور یہ کہ خود اللہ تعالیٰ اُمت محمدیہ کی تربیت کا انتظام کرتا رہے.چنانچہ
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعائنی گئی اور اس کا نتیجہ جو کچھ نکلا وہ تاریخ کے اوراق بتارہے
ہیں اور قیامت تک ایسا ہی ہوتا رہے گا اور جب بھی اسلام کی حفاظت کا سوال پیدا ہوگا اللہ تعالیٰ
خود اس کی حفاظت کے سامان پیدا کر دے گا.(ماخوذ از تفسیر کبیرزیر تفسير سورة النصر )
حضرت خلیفہ المسیح الرابع رحمہ اللہ فرماتے ہیں :
إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللهِ أَفْوَاجًا کہہ کر اللہ تعالیٰ
نے ایک خوشخبری دی ہے.فرمایا ایسا وقت آنے والا ہے کہ لوگ فوج در فوج اسلام میں
1032
Page 1041
داخل ہوں گے اور خدا کی طرف سے فتح آئے گی اور خدا کی طرف سے نصرت ملے گی.اس مضمون میں اللہ تعالیٰ نے نہ صرف خوشخبری دی بلکہ بعض ایسی باتوں کی طرف توجہ دلائی
ہے کہ جن کی طرف عام طور پر انسان توجہ نہیں کیا کرتا.جب بھی کسی کو فتح ملتی ہے، جب بھی
کسی کو نصرت عطا ہوتی ہے دماغ میں ایک کیڑا آ جاتا ہے کہ یہ میری کوشش سے ہوا ہے،
میری چالاکیوں سے ہوا ہے، میرے علم سے ایسا ہوا ہے، میں نے کیسی اچھی تنظیم کی تھی، کیسی
اچھی تدبیر کی تھی ، کیسا اچھا لیکچر دیا تھا، کیسی اچھی کوشش کی تھی.انسانی نفس انسان کو اس قسم
کے تو ہمات میں مبتلا کرتارہتا ہے.پس خدا تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ نصرت اور فتح تمہاری
کوشش سے ہوگی.تم اپنی کوشش سے تو دنیا میں کوئی تبدیلی نہیں پیدا کر سکتے تم اس لائق
نہیں ہو تم اس قابل نہیں ہو کہ عظیم الشان کام کر سکو اور دلوں میں ایک انقلاب بر پا کرسکو.یہ
خدا کا کام ہے اس لئے اللہ کی نصرت آئے گی، اللہ کی طرف سے فتح آئے گی اور یہ خدا ہی ہے
جولوگوں کو فوج در فوج اسلام میں داخل کرے گا.فرماتا ہے : إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَ الْفَتْحُ
وَ رَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللهِ أَفْوَاجًا - فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرُهُ إِنَّهُ كَانَ
توابا جب خدا کی طرف سے فتح و نصرت عطا ہو تو اس وقت تمہیں چاہئے کہ خدا کی تسبیح کرو اور
اس سے استغفار کرو.بظاہر تو اس کا فتح سے کوئی تعلق نہیں ہے.فتح کے وقت تو یہ کہا جاتا ہے
کہ شادیانے بجاؤ ، اچھلو اور کو دو اور جشن مناؤ لیکن خدا تعالیٰ نے ان چیزوں میں سے کسی کا ذکر
فرمایا.بلکہ فرمایا جب خدا کی طرف سے نصرت آئے اور فتح ملے.فَسَبِّحْ بِحَمْدِ
رَبَّكَ وَاسْتَغْفِرُہ.تو خدا تعالیٰ کی تسبیح بھی کرنا.اس کی حمد کے ترانے بھی گانا.اور استغفار بھی
کرنا.تاکہ تمہارے نفس میں انانیت کا اگر کوئی ادنی سا بھی کیڑا پیدا ہو تو وہ کچلا جائے ، تمہاری
توجہ اس طرف پھر جائے کہ جس ہستی نے یہ نصرت عطا کی ہے میں اس کی حمد کے گیت گاؤں،
جس نے ہمیں یہ فتح نصیب فرمائی ہے اس کی تسبیح کروں تسبیح وتحمید اس لئے ضروری ہے کہ
اس کے بغیر اس فتح کا فائدہ کوئی نہیں ہو سکتا جو فتح دین کی فتح ہوا کرتی ہے.اگر آپ تسبیح اور
نہیں
1033
Page 1042
تحمید کے بغیر دین میں کوئی فتح حاصل کریں گے تو وہ ضائع چلی جائے گی اور بجائے فائدہ کے
بسا اوقات نقصان بھی پہنچ سکتا ہے.دین کا ایک غلبہ تو مقدر ہوتا ہے لیکن بعض دفعہ وہ مقدر
ایسے وقتوں میں آجاتا ہے جب دین بگڑ چکا ہوتا ہے.خدا نے تو وہ وعدہ پورا کر دیا.اس نے
دین کو فتح عطا کر دی لیکن لوگ بگڑ چکے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے عملاً وہ فتح بیکار ہو جاتی ہے.چنانچہ ایسی کئی قومیں ہمارے سامنے ہیں جن کی تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ خدا نے تو ان کو فتح عطا
فرما دی لیکن بد قسمتی سے وہ لوگ بگڑ چکے تھے اور فتح سے استفادہ نہ کر سکے.اس لئے اللہ تعالیٰ
فرماتا ہے کہ جب تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت ملے اور فتح عطا ہو تو فَسَبِّحْ بِحَمْدِ
ربك.اپنے رب کی تسبیح کے ترانے گانا اور اس کی حمد کرنا.یعنی دو طرح کی قوتیں اپنے رب سے
حاصل کرنا.ایک تو یہ کہ تسیح کے ذریعہ خدا کے حضور یہ عرض کرنا کہ ہم تو نقائص سے پاک نہیں
ہیں ، ہماری تو ہر چیز میں غلطیاں ہیں اس لئے اے خدا! تو غلطیوں سے پاک ہے ہم تیری طرف
متوجہ ہوتے ہیں.اس فتح میں ہماری غلطیوں کے نتیجہ میں جو کمزوریاں رہ جائیں ان سے ان
قوموں کو محفوظ رکھنا جو اسلام میں داخل ہو رہی ہیں.یہ نہ ہو کہ ہم اپنی بدبختی سے اپنی کمزوریاں
ان میں داخل کر دیں اور چونکہ یہ بھی کمزوریوں سے پاک نہیں ہیں اس لئے یہ نہ ہو کہ جب یہ
لوگ ہمارے اندر آئیں تو اپنے بد خیالات اور بد رسوم اور کمزوریاں لے کر داخل ہو جائیں.اور
امر واقعہ یہ ہے کہ جب بھی مذاہب غلبہ پاتے ہیں یہ Process اور یہ واقعہ ضرور رونما ہو جاتا
ہے.چنانچہ ایک طرف تو یہ ہوتا ہے کہ داخل ہونے والے جب پہلوں کی کمزوریاں دیکھتے
ہیں تو ان میں سے بعض ٹھو کر کھاتے ہیں اور واپس پھر رہے ہوتے ہیں یعنی مرتد ہو رہے
ہوتے ہیں.وہ لوگوں کو قریب سے دیکھتے ہیں ، ان کو نظر آتا ہے کہ ان میں تو بہت سی
بیماریاں ہیں، یہ تو اتنے اچھے نہیں جتنے سمجھ کر ہم داخل ہوئے تھے تو دوسری طرف بعض لوگ جو
واپس نہیں جاتے بلکہ اکثر ہیں جو واپس نہیں جاتے مگر وہ ان کمزوریوں کا شکار ہو جاتے ہیں جو
پہلے موجود ہوتی ہیں.وہ کہتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا جس طرح پہلے تھے اس طرح اب بھی ہیں
1034
Page 1043
اور پہلے اگر کمز ور تھے تو یہ لوگ بھی تو کمزور ہیں ان کمزوریوں اور بدیوں میں مبتلا ہونے میں کوئی
حرج نہیں.پس وہ قوم بڑی بدقسمت ہوتی ہے جس کو خدا فتح نصیب کرے اور وہ خدا کی
عطا کردہ اس فتح کے مزاج کو بگاڑ دے.دوسری طرف یہ لوگ برائیاں لے کر آتے ہیں.چنانچہ دیکھ لیں اسلام کی تاریخ میں اکثر
بدعات اور نقائص ملکی حالات سے تعلق رکھتے ہیں.ہندوستان کی اور قسم کی بدعات ہیں، وہاں اور
قسم کی رسوم ہیں جنہوں نے اسلام میں رواج پایا، ایران کی فتح کے وقت اور قسم کی بدیاں داخل
ہوئیں.عیسائی آئے تو کچھ اور قسم کی بدیاں لے کر آئے ، یہودی داخل ہوئے تو وہ اپنے مزاج
کی بدیاں لے کر آئے، مشرک کچھ اور بدیاں لے کر آ گئے تو آنے والے بھی اپنی ساری
بدیاں چھوڑ کر نہیں آیا کرتے.وہ کچھ بدیاں ساتھ لے کر آتے ہیں جن کی اصلاح کرنی پڑتی
ہے.اس لئے اللہ تعالیٰ نے تسبیح کے ذریعہ ہمیں یہ پیغام دیا کہ نہ آنے والے پاک ہیں، نہ تم
پوری طرح پاک ہو.اگر تم نے اپنے رب
کی تسبیح نہ کی اور اس کی طرف متوجہ نہ ہوئے اور
عاجزانہ یہ عرض نہ کیا کہ اے خدا! نہ صرف یہ کہ ہماری بدیاں ان تک نہ پہنچیں بلکہ انہیں بھی پاک
فرمادے تا کہ ان کی بدیاں ہم میں داخل نہ ہوں.اس وقت تک یہ فتح تمہارے کسی کام نہیں آ
سکتی بلکہ ہو سکتا ہے کہ اس فتح کو تم بالکل اس لائق نہ رہنے دو کہ مذہبی تاریخ میں اس کی کوئی
حیثیت باقی رہے.یہ ایک لمبا مضمون ہے.میں اس سے اگلے قدم میں داخل ہوتا ہوں.اللہ تعالیٰ نے حمد کا پیغام دیا.خدا کی حمد کے گیت گانے کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ
اللہ تعالی گویا ہماری حمد کا پیاسا بیٹھا ہوا ہے کہ پہلے تسبیح کر دیں پھر حمد کر دیں تو اسے اس فتح کی
جز امل جائے گی جو اس نے عطا کی ہے.اگر کسی کے دماغ میں یہ خیال ہے تو نہایت لغو خیال
ہے.وہ تو تسبیح و تحمید سے بھی مستغنی ہے، وہ تو ساری کائنات کا مالک ہے، انسان پیدا ہو یا نہ ہو،
یہ زمین اور یہ زمانہ ہو یا نہ ہو وہ ساری کائنات پر حاوی ہے، سارے زمانوں پر حاوی ہے.یہ جو
پیغامات دیتا ہے یہ ہمارے فائدہ کے لئے دیتا ہے.فرماتا ہے جب خدا کی حمد میں داخل ہو
گے تو یہ دعا کرنا جس سے تمہارے دل میں بے قرار تمنا خود بخود اٹھنے لگے گی.اللہ کی ذات پر
1035
Page 1044
غور کرو گے اس کی صفات پر غور کرو گے تو پھر تمہارے دل سے یہ دعا نکلنی چاہئے کہ اے خدا!
جہاں بدیوں کا بائیکاٹ ہو جائے ، نہ وہ ہم سے لیں نہ ہم ان سے لیں ، وہاں حمد دونوں طرف سے
بہنے لگے.وہ اپنی خوبیاں لے کر ہمارے اندر داخل ہوں اور ہم اپنی خوبیاں ان کے اندر داخل کر
رہے ہوں اور ایک عظیم الشان قوم وجود میں آ رہی ہو.تو اسلامی فتح کا یہی وہ تصور ہے جسے
احمدیوں کو پیش نظر رکھنا چاہئے کیونکہ مجھے ایسے آثار نظر آ رہے ہیں کہ انشاء اللہ بہت جلد
فوج در فوج لوگ احمدیت میں داخل ہونے والے ہیں اور مشرق بعید میں خدا تعالیٰ نے نئی فتح
کے دروازے کھول دیتے ہیں.ایسے دلوں میں انقلاب برپا ہو رہے ہیں کہ وہ سننے کے لئے
تیار بیٹھے ہیں.جب اسلام کا پیغام سنتے ہیں تو شکوے کرتے ہیں اور کہتے ہیں تم لوگ پہلے کہاں
تھے، ہمارے پاس کیوں نہیں آئے.اس لئے میں نے سوچا کہ اس فتح نے تو آنا ہی آنا ہے.اب یہ خدا کی تقدیر ہے جو لکھی گئی.کوئی نہیں جو اس تقدیر کو بدل سکے.آپ ان لوگوں کو محبت
اور پیار کے ساتھ وصول کرنے کی تیاری کریں.اپنے دل صاف کریں، اپنے اخلاق اور اطوار
کو درست کریں، اپنے خیالات کو پاکیزہ بنائیں، اپنے اعتقادات کی حفاظت کریں، آپ پر
بہت بڑی ذمہ داریاں پڑنے والی ہیں.آپ ان کے میزبان بننے والے ہیں.اس لئے
بدیوں کے خلاف اپنے دفاع کو مضبوط کریں تا کہ جب ان نئی قوموں سے آپ کا وسیع طور پر
تعلق قائم ہو تو ان کی بدیوں کو رڈ کرنے والے ہوں اور اپنی بدیوں کو پہلے دُور کر دینے والے
ہوں یا استغفار کرتے ہوئے کم از کم ایسا انتظام کریں کہ وہ بدیاں ان میں داخل نہ ہوں.پھر حمد
کے ترانے گائیں.اپنے اندر خوبیاں پیدا کریں.اسلامی تعلیم پر عمل پیرا ہو کر اس دنیا میں جنت
پیدا کریں.اکثر لوگ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ کیا وہ Utopia ( ٹیٹو پیا یعنی مثالی معاشرہ ) جولوگوں
کے تصور میں ایک خواب ہے ایک کہانی ہے کہ دنیا میں ایک عظیم الشان سنہری زمانہ آ جائے
گا جس میں ہر طرف امن ہو گا اور انسان اس جنت کو پالے گا جس کی خاطر غالباً وہ یہ سمجھتے ہیں کہ
انسان کو پیدا کیا گیا ہے.تو میں ان سے کہا کرتا ہوں کہ وہ جنت تو قریب آ رہی ہے، وہ
1036
Page 1045
اسلام کی فتح ہی کی جنت ہے مگر اس کے لئے ہر احمدی کوزبردست تیاری کرنی پڑے گی.اسی
طرح ہر احمدی کو پھر حمد کے مضمون میں بھی داخل ہونا پڑے گا اس ارادے کے ساتھ کہ خدا کی
خاطر مجھ پر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان کو ادا کرنے کے لئے مجھے اپنے خیالات کو درست
کرنا ہے، اپنے اخلاق کو سنوارنا ہے، اپنی عادات کو سنوارنا ہے، اپنے مزاج کوسنوارنا ہے اور
یہ سب روزمرہ کی زندگی کے ساتھ تعلق رکھنے والے واقعات ہیں.یہ کوئی فرضی حمد نہیں ہے کہ
آپ نما ز میں چند منٹ کے لئے تصوراتی حمد کرلیں اور پھر باہر آ کر بھول جائیں کہ آپ نے کیا
کہا تھا.حالانکہ تسبیح و تحمید کا مضمون اور برائیوں کو دور کرنے کا مضمون تو روز مرہ کی زندگی میں
داخل ہو جاتا ہے، وہ خوابوں میں بھی ساتھ رہتا ہے.اٹھنے کے وقت بھی ساتھ رہتا ہے.جس
وقت آپ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی ساتھ ہوتا ہے.جس وقت آپ وضو کر رہے
ہوتے ہیں اس وقت بھی ساتھ ہوتا ہے، جس وقت آپ معاملات کر رہے ہوتے ہیں اس
وقت بھی ساتھ ہوتا ہے.بیوی بچوں کے تعلقات میں بھی اور غیروں کے تعلقات میں بھی ساتھ
ہوتا ہے.غرضیکہ ہر روز انسان کی زندگی میں ایسے بے حد اور بے انتہا مواقع نظر آتے ہیں
جہاں وہ اپنی بعض برائیاں دور بھی کر سکتا ہے، اگر وہ بیدار مغزی کے ساتھ اپنا مطالعہ کرے اور
بعض وہ خوبیاں اپنے اندر پیدا کر رہا ہوتا ہے مثلاً بول چال میں بداخلاقی کو چھوڑ دیتا ہے، کلام
میں تیزی اور مزاج میں درشتی کو نرمی میں بدل دیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ آج میں نے یہ برائی
چھوڑ دی ہے، اب میں نے وہ برائی چھوڑ دی ہے.اس طرح جب وہ خدا کی حمد کے گیت
گائے گا اور اس کی صفات کے مضمون میں ڈوبے گا تو الہی صفات کے رنگ پکڑنا شروع کر
دے گا اور اس طرح اخلاق کو درست کرنے کا اس سے بہتر طریق اور کوئی نہیں.جب آپ کہتے ہیں الْحَمدُ لله رب العالمین تو یہ حد ہی کا مضمون ہے.اللہ رب العالمین
ہے.تمام جہانوں کی پرورش کرنے والا ہے.رب کا مطلب ہوتا ہے کہ جو بھی خدا کا فیض
پائے اور جو اس سے تعلق جوڑے وہ پہلے سے بہتر ہونا شروع ہو جائے.اگر کسی انسان میں یہ
1037
Page 1046
مادہ پیدا ہو جائے کہ جو اس سے تعلق جوڑے وہ بہتر ہونا شروع ہو جائے تو وہ صفت ربوبیت کا
مظہر سمجھا جاتا ہے.یہ صفت سب سے زیادہ حضرت محمد مصطفی صلیم میں پیدا ہوئی کیونکہ آپ
اللہ تعالیٰ کی صفات کے مظہر اتم تھے.پارس پتھر کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ جو چیز اس سے لمس
کرتی ہے وہ سونا بن جاتی ہے.پارس پتھر کی محمد مصطفی علم کی جوتیوں کے مقابل پر کیا
حیثیت ہے.آپ جس جگہ سے گزرتے تھے اس جگہ کو تبدیل کرتے چلے جاتے تھے.آپ
نے ایک نہایت ہی حیرت انگیز انقلاب برپا کیا ہے.آپ نے ایک نہایت ہی ادنی اور
ذلیل سوسائٹی کو پکڑا ہے اور انتہائی بلند مقامات پر پہنچا دیا ہے.اس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی
صفت ربوبیت کا مظہر اتم.اتمام ربوبیت کا مضمون بہت وسیع ہے اور بڑا پھیلا ہوا ہے اس
کے اندر خدا کی کئی صفات آ جاتی ہیں جو ربوبیت کے تابع جلوہ دکھاتی ہیں.قرآن کریم میں
جہاں جہاں رب کا ذکر ہے وہاں کبھی کسی صفت کا اس ضمن میں ذکر ہے اور کبھی کسی صفت کا
اس ضمن میں ذکر ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ ربوبیت کے دروازے سے حمد
میں داخل ہوں گے تو آپ کے لئے ایسی بہت سی نئی نئی گلیاں کھلیں گی ، نئے نئے راستے کھلیں
گے کہ جن میں سفر کرتے ہوئے آپ پہلے سے زیادہ حسن اختیار کرتے چلے جائیں گے.پس
یہ ہے حمد کا مضمون جو آپ کی روز مرہ کی زندگی میں داخل ہو جائے گا.پھر فرمایا الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ صفت رحمان کے اندر تو یہ جلوہ ہے کہ کوئی انسان مانگے یا
نہ مانگے وہ فیض آپ اس کو پہنچا دیں.وہ ناشکرا بھی ہو تب بھی آپ اس کو فیض پہنچائیں ، وہ
آپ کو گالیاں دینے والا بھی ہوتب بھی آپ اس کو فیض پہنچائیں.چنانچہ رحمانیت وہ عمومی فیض
ہے جس میں سارے بنی نوع انسان شامل ہیں.اس کے بعض پہلوؤں کے متعلق میں پہلے بیان
کر چکا ہوں آج میں صرف اتنا ہی اس کے متعلق کہتا ہوں کہ رحمانیت کے بعض پہلو ایسے ہیں
جن میں کافر ،مشرک بھی برابر کا شریک ہوتا چلا جاتا ہے اور کوئی جو مرضی کہے خدا کو گالیاں
دے، اس کے متعلق گندی زبان استعمال کرے، خدا کے ماننے والوں کو دکھ دے تب بھی
1038
Page 1047
صفت رحمانیت کے ماتحت قدرت اس پر فضل کرنے سے نہیں رکھتی.تبلیغ کا بھی رحمانیت سے
ایک گونا تعلق ہے کیونکہ تبلیغ کی راہ میں خدا کے بندے آپ سے بعینہ وہ سلوک کرتے ہیں جو
بعض ظالم بندے اپنے رحمان خدا سے بھی کر رہے ہوتے ہیں.چنانچہ آنحضرت معالم نے
لوگوں کے ہاتھوں دکھ پر دکھ اٹھائے لیکن آپ بنی نوع انسان کو فائدہ پر فائدہ پہنچاتے چلے
گئے اور اپنے عمل سے یہ ثابت کر دکھایا کہ خدا کی صفت رحمانیت سب سے زیادہ آپ کے وجود
میں جلوہ گر ہوئی.پھر رحیمیت ہے.اس کا ایک تقاضا یہ ہے کہ جب آپ کسی پر رحم کریں، اس کے فائدہ کی
بات سوچیں تو ایک دفعہ کر کے بھول نہ جایا کریں.جس طرح خدا تعالیٰ انسان پر بار بار فضل اور
رحم لے کر آتا ہے اسی طرح آپ کے ذریعہ بھی بنی نوع انسان
اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور فضل حاصل
کریں اور آپ کے اندر بھی صفت رحیمیت جلوہ گر ہو یعنی آپ کی کوشش یہ ہو کہ آپ کے
ذریعہ اللہ تعالیٰ بنی نوع انسان پر بار بار فضل فرمائے.چنانچہ تبلیغ کر کے جولوگ بھول جاتے
ہیں وہ رحمان بننے کی تو کچھ کوشش کرتے ہیں لیکن رحیم نہیں بن سکتے اور پھلوں کا تعلق رحیمیت
سے ہے.دنیا میں جتنا بھی پھلوں کا نظام ہے اس کا تعلق رحیمیت سے ہے.رحمانیت وہ مواد
عطا کرتی ہے جس کے نتیجہ میں چیزیں جب ایک دوسرے کے ساتھ عمل میں آتی ہیں تو پھل لگ
سکتے ہیں اور رحیمیت ہے جو پھل عطا کرتی ہے.یہ رحیمیت کا تقاضا ہے کہ ہر محنت کا اچھا بدلہ دیتی اور ہر کوشش کے نتیجہ میں اس سے کئی
گنا زیادہ عطا کرتی ہے.چنانچہ آپ دیکھ لیں.پھلوں کے مضمون میں ہر جگہ آپ کو رحیمیت
کا کرشمہ نظر آئے گا.مثلاً اگر خدا تعالیٰ دنیا میں محنت کا دس گنا یا سو گنا یا سات سو گنا بدلہ نہ دے
رہا ہوتا تو یہ ساری زندگی مدتوں سے پہلے فنا ہو چکی تھی.Evolution یا ارتقا جس رنگ میں
بھی ہوا ہے وہ وجود میں ہی نہ آتا.یہ دراصل رحیمیت کا کرشمہ ہے کہ وہ محنت کا بدلہ دے رہی
ہے اور جتنی محنت کی جاتی ہے اس سے کئی گنا زیادہ بدلہ دیتی ہے.زمیندار کو دیکھیں وہ محنت کر
1039
Page 1048
کے ایک بیج کا دانہ کھیت میں ڈالتا ہے اور وہ بعض صورتوں میں قرآن کریم کے مطابق کئی سو گنا
بھی بڑھ سکتا ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے.پس پھل کے اس نظام کا رحیمیت سے تعلق ہے.خدا تعالیٰ کی قدرت صفت رحیمیت
کے ماتحت بار بار وہ موسم لے کر آتی ہے اور وہ حالات پیدا کر دیتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ پھل
لگیں اور انسان خدا تعالیٰ کی رحیمیت کے کرشمے دیکھے.غرض تبلیغ میں بھی پھل تب لگے گا اور
بنی نوع انسان کو فائدہ پہنچانے کے آپ تب موجب بنیں گے جب آپ بڑے صبر کے ساتھ
اور بڑی ہمت کے ساتھ اور نہایت مستقل مزاجی کے ساتھ خدا تعالیٰ کی صفت رحیمیت کے
ساتھ تعلق جوڑ لیں گے اور رحیمیت کے تابع بھی بہت سی صفات ہیں.چنانچہ قرآن کریم کا یہ
ایک عجیب اسلوب ہے کہ خدا تعالیٰ کی بنیادی صفات جو سورۃ فاتحہ میں بیان ہوئی ہیں ان کو
ادل بدل کر مختلف مواقع پر پیش کرتا چلا جاتا ہے جس سے انسان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی صفات
کی ایک تصویر کھلتی چلی جاتی ہے جن میں صفت رحیمیت کار فرما ہوتی ہے اور یہ حقیقت روشن
ہونے لگتی ہے کہ خدا تعالیٰ کی تمام صفات ان چار بنیادی صفات ہی کا پر تو ہیں جو سورۃ فاتحہ میں
بیان ہوئی ہیں.ایک بھی صفت ان سے باہر نظر نہیں آئے گی.رحیمیت کا عدم کیا ہے؟ یہ
صفت نہ ہو تو کیا پیدا ہوتا ہے؟ خدا کی بعض منفی صفات ( منفی تو کوئی بھی چیز نہیں ) ان معنوں
میں کہ قرآن کریم میں آپ کو رحیمیت کے برعکس صفات نظر آنے لگیں گی.اسی طرح
رحمانیت نہ ہو تو دنیا میں کیا تباہی مچتی ہے وہاں آپ کو خدا تعالیٰ کی بعض ایسی صفات نظر آئیں
گی جو رحمانیت کے الٹ ہیں اور ایسی صفات ان قوموں کے لئے ظاہر ہوتی ہیں جو رحمانیت
سے تعلق نہیں جوڑتیں.پس بظاہر تو حمد کی صفات ہوتی ہیں لیکن انہی کے اندر تسبیح والا مضمون بھی آجاتا ہے اور
سورۃ فاتحہ کا نظام ایک مکمل نظام ہے اس پر غور کرتے ہوئے جب آپ حمد کے مضمون میں
داخل ہوں تو تفصیل سے سوچا کریں کہ ہم نے کس خدا سے تعلق جوڑا ہے اور کیا ہم بندوں کے
1040
Page 1049
لئے ویسا بن رہے ہیں یا نہیں.اگر ویسا بنیں گے تو لازماً پھر آخر پر وہ نتیجہ پیدا ہوگا جس کی
طرف سورہ فاتحہ ہمیں لے کر جا رہی ہے.مثلاً انسان رب بن جائے یعنی اپنے رنگ میں
ربوبیت کی صفات پیدا کر لے، وہ رحمان بن جائے یعنی اپنے رنگ میں اور اپنے محدود دائرہ میں
وہ اپنے اندر رحمانیت کی صفات پیدا کر لے، رحیم بن جائے اور اپنے دائرہ میں اور اپنی توفیق اور
استطاعت کے مطابق رحیمیت کی صفات پیدا کر لے تو لازماً پھر ملِكِ يَوْمِ الدِّينِ تک پہنچ
جاتا ہے.چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مضمون کو کھولا اور فرمایا کہ
سارے انبیاء میں سے صفت مالکیت کے کامل مظہر صرف حضرت محمد مصطفی ملایم بنے ہیں.یعنی آپ صفت مالکیت کے مظہر اتم تھے.آپ نے اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت کی کامل
صفات اختیار فرمائیں.صفت رحمانیت کی بھی کامل طور پر صفات اختیار فرمائیں اور پھر آپ
نے حیرت انگیز طور پر رحیمیت کی صفات بھی اختیار فرمائیں یہاں تک کہ نتیجہ آپ مالکیت
تک پہنچ گئے یعنی اس خدا سے آپ کی محبت کا کامل تعلق پیدا ہو گیا جو مالک ہے.ہر چیز اس
کے قبضہ قدرت میں ہے اور ہر انجام اس کے ہاتھ میں ہے.خدا تعالیٰ نے آپ کو مالکیت
میں شامل کر لیا.آپ کو وہ بادشاہت عطا کی جو خدا کی بادشاہت تھی.آپ کی زبان خدا کی
زبان بن گئی ، آپ کا ارادہ خدا کا ارادہ بن گیا، آپ کا غضب خدا کا غضب ٹھہرا اور آپ کا رحم
اللہ کا رحم کہلایا.یہ ہے سورۃ فاتحہ میں بیان ہونے والی مالکیت کی صفت کا مفہوم جسے حضرت
مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے سامنے کھول کر بیان فرمایا ہے.آپ نے فرمایا ہر
کامیابی کا راستہ یہ ہے کہ انسان ان تین صفات کو اختیار کر کے اپنے خالق و مالک رب سے
تعلق جوڑے تب خدا کی صفت مالکیت ان تین صفات کو چمکا دیتی ہے، ان کے استعمال کو
ایک نئی شان بخشتی ہے.ایک انسان اگر صفت رحمانیت کا مظہر ہو اور صفت مالکیت کا نہ ہو تو
اس کی حد گو یا ایک معین حد ہے اس سے آگے وہ نہیں بڑھ سکتا.آپ کو کسی شخص پر کتنا ہی رحم
کیوں نہ آ رہا ہو، آپ کا کتنا بھی دل چاہیے کہ آپ اس کو سب کچھ عطا کر دیں ، وہ مانگے نہ
1041
Page 1050
مانگے آپ اس کو عطا کر دیں لیکن آپ صفت مالکیت کے مظہر نہ بنیں تو آپ کی صفتِ
رحمانیت کیا جلوہ دکھا سکتی ہے.رحیمیت کی صفت اختیار کریں ، ربوبیت کی اختیار کریں جو
چاہیں کریں اگر صفت مالکیت کا شرف حاصل نہ ہو تو یوں معلوم ہوتا ہے ہر صفت اپنی ذات
میں سکڑ کر رہ گئی ہے اس میں کوئی بھی طاقت نہیں رہی.پس جب خدا تعالیٰ کے بندے خدا کی خاطر ربوبیت اختیار کرتے ہیں ، رحمانیت اختیار
کرتے ہیں اور رحیمیت اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی کمزوریوں پر رحم فرماتا ہے.اللہ
تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو! میرے بندے میرے جیسا بنے کی کوشش کرتے ہیں ، میرے حسن
کی صرف زبان سے تعریف نہیں کرتے بلکہ عمل کو بھی میری صفات کے رنگ میں ڈھالنے کی
کوشش کرتے ہیں لیکن بچارے مجبور ہیں ان کے پاس کچھ طاقت نہیں ہے کہ وہ میرے جیسا
بن سکیں.تب خدا کی صفت مالکیت جوش میں آتی ہے اور وہ ان کو درجہ بدرجہ مالکیت میں
شامل کر لیتی ہے اور اس مقام پر سب سے زیادہ حضرت محمد مصطفی صلیم نے اللہ تعالی سے
مالکیت کی صفات پائیں.نہ صرف خود یہ صفات پائیں بلکہ اپنے غلاموں کو بھی عطا کیں چنانچہ
آنحضرت علا السلام نے جب یہ فرمایا کہ عسى رُبَّ اشْعَكَ أَغْبَرَ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَابَرَهُ
(مستدرك حاكم جلد 4 صفحه 364 - الجامع الصغير للسيوطى الجزء الثانى باب الراء)
تو اسی مضمون کی طرف اشارہ فرمایا تھا.تم میرے مقام کو سمجھنا چاہتے ہو تو تمہاری عقلیں ،
تمہارا علم ، تمہاری فراست اور تمہارا ادراک کوتاہ ہے تم اس تک نہیں پہنچ سکتے.تم میرے
غلاموں کی شان دیکھو.ان میں سے ایسے بھی ہیں جن کے بالوں میں خاک اڑ رہی ہوتی ہے جن
کا حال پراگندہ ہوتا ہے لیکن جب وہ خدا پر قسم کھا لیتے ہیں کہ خدا کی قسم یہ واقعہ ہوگا تو خدا ایسا
واقعہ ضرور کر دیا کرتا ہے.اس کو کہتے ہیں مالکیت میں شامل کر دینا.تو صفت مالکیت ایسی
نہیں ہے جو آپ اپنی ذات سے یا اپنی کوشش سے اختیار کر سکیں.انسان کے پاس کچھ
نہیں ہے کیونکہ جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے ربوبیت رحمانیت اور رحیمیت کی توفیق بھی
1042
Page 1051
اللہ تعالی ہی دے سکتا ہے.صرف آپ کا ایک ارادہ ہے، نیک تمنا ہے کہ ہم ایسا بننے کی
کوشش کریں.جب آپ پوری نیت کے ساتھ ، پوری وفا کے ساتھ ، پورے عجز کے ساتھ،
پورے پیار اور محبت کے ساتھ اپنے رب کے رنگ میں رنگین ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو
پھر اس کی صفت مالکیت جلوہ دکھاتی ہے اور وہ انسان کو مالک بنا دیتی ہے.پس اگر احمدی نے اس سارے زمانہ کی تقدیر بدلنی ہے تو اس کا یہی ایک طریق ہے جو مجھے
معلوم ہے اس کے سوا اور کوئی طریق نہیں ہے.یہی قرآن کریم کی تعلیم ہے، یہی حضرت
محمد مصطفی صلی کی سنت ہے اور یہی اس کی تفسیر ہے جو آپ نے مختلف وقتوں میں بیان
فرمائی.پس مجھے نظر آ رہا ہے کہ خدا کی قدرت مالکیت کے جلوے دکھانے کے لئے تیار
ہے.آپ کو مبارک ہو کہ خدا تعالیٰ بنی نوع انسان پر اور احمدیت کی قربانیوں پر رحم فرما رہا
ہے.وہ جان چکا ہے کہ احمدی پورے خلوص اور محبت اور وفا کے ساتھ اپنا سب کچھ اس کی راہ
میں فنا کرنے کے لئے تیار ہو رہے ہیں.چنانچہ ہم پر اس کے پیار کی نظر میں پڑ رہی ہیں
اللہ تعالی مالک ہے وہ لوگوں کے دلوں میں تبدیلیاں فرما رہا ہے.خطبہ جمعہ حضرت خلیفتہ اریح الرابع رحمہ اللہ، فرمودہ 14 اکتوبر 1983ء.خطبات طاہر جلد دوم صفحہ 513 تا524)
اسی طرح حضرت خلیفہ اسیح الرابع رحمہ اللہ نے خطبہ جمعہ فرمودہ 11 اپریل 1986 ء میں
سورۃ النصر کی تلاوت کے بعد فرمایا:
دین کی اصطلاح میں جس چیز کا نام فتح ہے اور جس چیز کو نصرت قرار دیا جاتا ہے وہ دنیا
کی اصطلاح میں فتح اور نصرت کہلانے والی چیز سے بالکل مختلف چیز ہے.ان دونوں کے
مزاج مختلف ہیں ، ان کی نوعیت مختلف ہے، ان کے رخ بالکل مختلف ہیں اور ایک کا کردار
دوسرے کے کردار سے اتنا بعید ہے، اتنا فاصلہ رکھتا ہے جیسے بُعْدَ الْمَشْرِ قَيْنِ ہو.چنانچہ قرآن کریم نے اس سورۃ میں جو فتح و نصر کا نقشہ کھینچا ہے اس کی ظاہری الفاظ میں جو
شکل ظاہر ہو رہی ہے اگر اس کی باطنی حقیقتوں میں ڈوب کر غور نہ بھی کریں تو ظاہری شکل و
صورت ہی دنیا کی فتح ونصر کی ظاہری شکل وصورت سے بالکل مختلف دکھائی دیتی ہے.دنیا میں
1043
Page 1052
تو فتح نام ہے دوسروں کی زمینوں کا سر کرنا، ان کے ملکوں میں گھس کر ان کی زمینوں کو تہ و بالا کرنا
اور فوج در فوج دوسرے ممالک پر قبضہ کر لینا.قرآن کریم جس فتح کا ذکر فرما رہا ہے اس کا رخ دیکھیں کتنا مختلف ہے.فرماتا ہے
يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللهِ أَفْوَاجًا کہ جس فتح کی ہم بات کرتے ہیں اس میں دشمن جوق در جوق اور
فوج در فوج تمہاری یعنی اسلام کی سرزمین میں داخل ہوگا.اس میں بہت سے لطیف اشارے ملتے ہیں جن میں سے بعض کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں
اور ایک خصوصیت کے ساتھ آج بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اس سورۃ میں جبر کی کلیہ نفی کر دی گئی ہے.يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللهِ أَفواجًا میں ایک تو رخ مختلف یہ نہیں فرمایا کہ اسلامی فوجیں دندناتی ہوئی
غیروں کی سرزمینیں فتح کر رہی ہوں گی بلکہ فرمایا دشمن کی فوجیں جوق در جوق اور فوج در فوج اسلام کی
سرزمین میں داخل ہو رہی ہوں گی اور فوج کشی غیر کی طرف سے اسلام کی طرف ہے اور اسلام کی
طرف سے جبراً ان کو گھسیٹ کر لانے کا کوئی تصور ہی اس میں نظر نہیں آتا.تو لا إكراه في الدِّينِ (البقرہ 257) میں جس آزادی مذہب اور آزادی ضمیر کا اعلان
کیا گیا تھا اس
کی عملی تصویر نہایت ہی حسین رنگ میں قرآن کریم نے اس چھوٹی سی سورۃ میں
کھینچ دی اور فتح کے شادیانے کیسے بجائے جاتے ہیں، کس طرح ببانگ دھل اعلان کئے
جاتے ہیں کہ آخر ہم فتح یاب ہوئے ، اس کے متعلق فرماتا ہے :إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَ الْفَتْحُ وَ
رايت النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللهِ أَفْوَاجًا - فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبَّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا -
کہ جب تم یہ عظیم الشان فتح دیکھو تو اس فتح کے شادیانے اور نظارے اس طرح بجاؤ کہ تمہارے
ہونٹوں پر خدا کی تسبیح ہو اور تحمید ہو اور بار بار استغفار کر رہے ہو، یہ کہتے ہوئے کہ اے خدا ہم تو
اس لائق نہیں تھے کہ جو تو نے ہمیں عطا کیا ، ہماری ذاتی کوششوں سے ہمیں کچھ بھی حاصل
نہیں ہوا، جو کچھ ہوا تیری عطا ہے.یہی نہیں بلکہ ہماری غلطیوں کے باوجود ہمیں عطا کیا گیا
ہے کیونکہ تسبیح کا مضمون یہ بتاتا ہے کہ جو کچھ ہے تیری ہی طرف سے ہے اور تو ہی ہے جو
1044
Page 1053
غلطیوں سے پاک ہے، تو ہی ہے جس کی تدبیر کامل ہے اور اس میں کوئی رخنہ نہیں اور تیری ہی
تدبیر کے ذریعہ فتح حاصل ہوئی اور استغفار کا مضمون یہ بتا تا ہے کہ ہم اس کے باوجود کہ تیری
تدبیر غلطیوں سے پاک تھی اس پر عمل پیرا ہوتے ہوئے ہم نے غلطیاں کیں.جو نقشے تو نے
بنائے تھے اسلام کی فتح کے ان
کی اینٹیں رکھنے والے معمار تو ہم تھے مگر ہم نے اینٹیں غلط رکھیں،
بار بار نقشے کی خلاف ورزی کی ، بار بار ایسے رخ پر غلطی سے اینٹیں رکھ دیں کہ جس کے نتیجہ میں اس
عمارت میں رخنے پیدا ہو سکتے تھے اس لئے ہم استغفار کرتے ہیں.تو ہمیں بخش ، ہم اس فتح کے
لائق نہیں، ہماری غلطیوں کے باوجود عطا ہونے والی فتح ہے.تو دیکھئے کتنا مختلف رخ ہے اور کتنا
مختلف مزاج ہے، کتنے مختلف تقاضے ہیں فتح مند فوجوں کے ساتھ وابستہ.پس جماعت کو دینی فتح کو دنیا کی فتح کے ساتھ باہم دیگر اس طرح ملا نہیں دینا چاہئے کہ
اشتباہ پیدا ہو جائے کہ گویادین کی فتح اور دنیا کی فتح ایک ہی چیز کے دو نام ہیں.میں سمجھتا ہوں کہ بعض اسلامی مؤرخین نے یہغلطی کر کے اسلام کو شدید نقصان پہنچایا ہے.جب مسلمان بادشاہوں نے بعض دیگر ممالک کو فتح کیا وہ ان کی سیاسی فتوحات تھیں.وہاں
يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللہ افواجا کا کوئی نقشہ آپ کو نظر نہیں آئے گا.اس کے برعکس وہ ایک
سیاسی غلبہ تھا جہاں تلواروں کے زور سے اور تیر و تفنگ کے زور سے بعض فوجیں بعض دوسرے
ملکوں میں داخل ہورہی تھیں.وہاں بحث یہ تو اٹھائی جاسکتی ہے کہ سیاسی اقدار کے لحاظ سے،
سیاسی اخلاقی تقاضوں کے اعتبار سے کسی ایک ملک کو کسی دوسرے ملک کے خلاف فوج کشی
کا حق تھا کہ نہیں تھا.یہ تو جائز ہے لیکن ان سب جنگوں کو اسلامی جہاد کا نام قرار دینا اور ان
سب فتوحات کو اسلامی فتوحات قرار دینا یہ درست نہیں ہے.دراصل اس زمانے میں جو فاتح اسلام تھے وہ تو بزرگ اور اولیاء اور فقیر اور درویش تھے
جو قطع نظر اس سے کہ سیاسی حالات کیا ہیں دن رات اسلام کی خدمت میں مصروف تھے.ہندوستان کی تاریخ پر ہی نظر ڈال کر دیکھ لیں تو ہندوستان کا مسلمان فاتح تو بابر کو قرار دیا جاسکتا
ہے لیکن اسلامی فاتح قرار نہیں دیا جاسکتا.اسلامی فاتح کا نام پانے والے بزرگ تو
1045
Page 1054
نظام الدین اولیاء جیسے بزرگ تھے اور ایسے بے شمار لوگ جو دھونی رما کر بیٹھ گئے اور یہ
عہد لے کے اپنی ساری زندگی اس عہد کی ایفاء میں صرف کر دی کہ ہم ان جاہلوں کو، ان اندھیروں
میں بسنے والوں کو خدا کی طرف سے علم اور عرفان عطا کریں گے اور قرآن کا جاری کردہ نور عطا
کریں گے.پس جماعت احمدیہ کو کبھی بھی اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کرنا چاہئے.آنحضرت علی کو جب اسلامی فتوحات کے ساتھ یہ خوش خبریاں بھی دی گئیں کہ ان
فتوحات کے ساتھ ان کے عقب میں لازماً سیاسی فتوحات بھی آئیں گی اور قیصر و کسریٰ کی
چابیاں بھی بعد میں آنے والے مسلمان کے ہاتھ میں تھمادی جائیں گی اور یمن کے محلات کے
دروازوں کو آپ نے دیکھا اور شام کے سرخ محلات کو اور ایران کے سفید محلات کو اپنی
آنکھوں کے سامنے آپ نے دیکھا تو اس کے نتیجہ میں آپ فکرمند ہو گئے.خدا کی تکبیر بھی کی،
خدا کی تسبیح و تحمید بھی فرمائی لیکن ایک گہرا فکر آپ کو لاحق ہو گیا.چنانچہ اس فکر کا اظہار آپ
نے اس طرح فرمایا کہ ایک موقع پر صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم پر نعمائے دنیا
کے دروازے کھولے جائیں گے یہاں تک کہ تم اپنے گھروں کو اس طرح سجاؤ گے جیسے خانہ
کعبہ کو سجایا جاتا ہے.یہ فرما کر آپ نے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے راہ حق کے درویشوں سے
فرمایا لیکن سنو تم جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہو تمہاری حالت ان آنے والے لوگوں سے
بدرجہ ہا بہتر ہے (مسند احمد بن حنبل جلد 2 حدیث نمبر 19205).پس آپ کے
نزدیک فتح دین کی فتح تھی ، فتح اخلاق کی فتح تھی، فتح کردار کی فتح تھی، فتح اپنے نفس پر غالب
آنے کا نام تھا اور وہ نعمتیں ہی نعمتیں تھیں جو روحانی نعمتیں تھیں اور ان کے مقابل پر بعد میں آنے
والی دنیاوی فتح سے تعلق رکھنے والی نعمتوں کی حضرت اقدس محمد مصطفی صیام کی نظر میں کوئی بھی
قیمت نہیں تھی.اسی طرح حضرت ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ آنحضرت علیم نے فرمایا کہ جن
چیزوں سے میں تمہارے متعلق ڈرتا ہوں ان میں سے دنیا کی زیب وزینت بھی ہے جو تم پر
1046
Page 1055
چاروں طرف سے کھول دی جائے گی.اس پر ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول
اللہ کیا خیر
شر کو بھی ساتھ لائے گا؟ یعنی ایک طرف تو یہ خیر کی باتیں ہیں، خوش خبریاں بھی بیان کی جاتی
ہیں.دوسری طرف آپ ڈرا رہے ہیں.تو کیا خیر شر کو بھی ساتھ لائے گا؟ روایت کرنے والے
بتاتے ہیں کہ اس پر حضور اکرم صلیہ خاموش ہو گئے اور سوال کرنے والے کو جواب نہ دیا.جب ہم نے آپ کے چہرے کو دیکھا تو اس وقت محسوس ہوا کہ آپ پر وحی نازل ہورہی ہے اور
اسی حالت میں آپ نے اپنے ماتھے سے پسینہ پونچھا اور پھر پوچھا کہ وہ سوال کرنے والا کہاں
ہے؟ اس پر ہم سمجھ گئے کہ محبت اور پیار سے اس کا نام لے رہے ہیں، پسندیدگی سے لے رہے
ہیں ، آپ کو سوال پسند آیا تھا اس کا جواب آ گیا ہے.تو جب بتایا گیا تو آپ نے فرمایا دیکھو
خیر شر کو جنم نہیں دیا کرتی ، خیر سے شر پیدا نہیں ہوتا لیکن تم دیکھتے ہو کہ جب بہار آتی ہے تو بہار
میں اُگنے والی فصلوں کے ساتھ ایسی جڑی بوٹیاں بھی تو اُگ آتی ہیں جن کو کھانے سے لوگ
مرجاتے ہیں یا مر سکتے ہیں (بخاری کتاب الزکوۃ حدیث نمبر 1372).تو معلوم ہوتا ہے کہ
اس وحی میں خدا تعالیٰ نے آنحضرت صلی لا علم کو اس سوال کا یہ جواب سکھایا.تو ظاہری فتح بھی جب مسلمانوں کو نصیب ہوتی ہے تو اس کے نتیجہ میں بھی وہ خیر حاصل
کر سکتے ہیں.ظاہری فتح کا نام شر نہیں رکھا گیا.شر اس بات کا نام رکھا گیا ہے کہ ظاہری فتح
کے ساتھ جو انسان کی روحانی زندگی کو مارنے والی اور مہلک جڑی بوٹیاں اگتی ہیں.نعمتوں
کے نام پر بعض ایسی چیزیں حاصل ہوتی ہیں جو انسانی زندگی کو تباہ کرنے والی ہوتیں ہیں.اگر
ان سے احتراز کرو تو ظاہری فتح بھی ایک رنگ میں دین کے تابع ہو سکتی ہے اور حقیقی نعمت شمار
کی جاسکتی ہے.چنانچہ اسی موقع پر آنحضرت علی نے پھر فرمایا کہ دیکھو مومن کو جو مال عطا
ہوتا ہے، جو
نعمتیں ملتی ہیں وہ نعمتیں بنتی ہیں جب وہ ان سے خدا کے حق ادا کرتا ہے.جب وہ اس
کی راہ میں خرچ کرتا ہے، غریبوں کے اوپر خرچ کرتا ہے، مصیبت زدگان پر خرچ کرتا ہے اور خرچ
کی کئی اقسام بتائیں کہ اس طریق پر نعمتیں نعمتیں بھی رہ سکتی ہیں اور عذاب میں تبدیل نہیں ہوتیں.لیکن یہ ایک ثانوی چیز ہے.حقیقی نعمت حقیقی خیر حقیقی خوش خبری اسی بات میں ہے کہ دین
1047
Page 1056
کو غلبہ عطا ہو جو اجسام پر غلبہ نہیں ہوتا بلکہ دلوں پر غلبہ پر ہوتا ہے، وہ دوسروں کی زندگیاں لے
کر غلبہ نہیں ہوتا بلکہ دوسروں کو زندگیاں عطا کر کے غلبہ ہوتا ہے.اس لئے اسلام کا غلبہ از سر نو
روحانی زندگی کا غلبہ ہے، اسلام کا غلبہ وہ قیامت ہے جس میں شیطان پر موت آتی ہے لیکن سچی
اور سعید روحیں نئی زندگی پاتی ہیں.احمدیت کو ہمیشہ اپنی نظریں اس نکتہ کی طرف گاڑے رکھنی
چاہئیں اور ایک لمحہ کے لئے بھی اس سے غافل نہیں ہونا چاہئے ورنہ دنیا کی فتوحات ، دنیا کے
غلبے، دنیا کے انقلاب ان کو غلط راہوں پر ڈال دیں گے ، ان کی تو جہات کے رخ بدل دیں
گے اور ان کو محسوس بھی نہیں ہوگا کہ خدا تعالیٰ نے جو نعمتیں ان کو عطا فرمائی تھیں وہ کس طرح
انہوں نے اپنے ہاتھ سے ضائع کردیں.“
اسی طرح حضور رحمہ اللہ نے فرمایا:
حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں : ” خدا تعالیٰ نے مجھے مخاطب کر کے
لفظوں میں فرمایا ہے آنا الْفَتَاحُ افْتَحُ لَكَ.تَرَى نَصْرًا عَجِيبًا وَ يَخِرُّونَ عَلَى
الْمَسَاجِدِ".میں فتاح ہوں.فتاح کہتے ہیں وہ ذات جو اندھیروں کو روشنی میں پھاڑ کر تبدیل کر دیتی
ہے جو جہالت کو علم میں بدل دیتی ہے اور جو معاملات کو کھول دیتی ہے اور قضا جاری کرتی
ہے.چنانچہ فتح الله عَلَيْهِ کا ایک معنی عربی کی لغت کی رو سے یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس کو
علم و عرفان عطا کیا اور ایک معنی اس کا یہ بھی ہے کہ میں غلبہ عطا کرنے والا ہوں یعنی شرف اور
بزرگی اور علم کی چابیاں رکھتا ہوں، ان کے دروازے کھولنے والا ہوں، روشنی کے باب کھولنے
والا ہوں اور غلبہ بھی عطا کرنے والا ہوں.لیکن کس قسم کا غلبہ؟ فرمایا : ترى نَضْرًا عجيبًا.اے
میرے پیارے بندے جو میں نضر تجھے عطا کرنے لگا ہوں وہ عام دنیا کی نظر سے مختلف
ہوگی تڑی نَضرا عجیبا تو عجیب ہی قسم کی نصرت دیکھے گا میری طرف سے.اور وہ کیا ہے؟
وَ يَخِرُّونَ عَلَى الْمَسَاجِدِ.وہ نصرت اس طرح ہوگی کہ احمدی اپنی مساجد پر، اپنی سجدہ گاہوں
پر اوندھے منہ گر جائیں گے....کیسا پیارا نقشہ کھینچا ہے.تَرَى نَصْرًا عَجِيْبًا وَ يَخِرُّونَ عَلَى
1048
Page 1057
الْمَسَاجِدِ ایسی عجیب نضر دیکھو گے تم کہ اس وقت خدا کے بندے اوندھے منہ سجدہ گاہوں پر گر
پڑیں گے اور ساتھ یہ فرمایا، اسی تحریر میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں:
اور ایک الہام میں چند دفعہ تکرار اور کسی قدر اختلاف الفاظ کے ساتھ فرمایا کہ میں تجھے
عزت دوں گا اور بڑھاؤں گا اور تیرے آثار میں برکت رکھ دوں گا یہاں تک کہ بادشاہ تیرے
کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گئے...فرماتے ہیں:
آسمانی فیصلہ، روحانی خزائن جلد 4 صفحه 342)
یکیں بڑے دعوے اور استقلال سے کہتا ہوں کہ میں سچ پر ہوں اور خدا تعالیٰ کے فضل سے
اس میدان میں میری ہی فتح ہے ( یعنی سچ کے میدان میں.یادرکھیں آپ کی فتح سچ کے میدان
میں ہے ) اور جہاں تک میں دور بین نظر سے کام لیتا ہوں تمام دنیا اپنی سچائی کے تحت اقدام
دیکھتا ہوں“
کتنا عظیم الشان کلام ہے ”جہاں تک میں دُور بین نظر سے کام لیتا ہوں تمام دنیا اپنی سچائی
کے تحت اقدام دیکھتا ہوں.دور بین نظر نے بتایا کہ خدا کے فضل کے ساتھ آپ کے ساتھ بھی
یہ وعدہ قائم ہے.اس میں عظیم الشان پیش گوئی ہے اور بہت ہی لطیف اور گہرا کلام ہے جہاں
تک میں دور بین نظر سے دیکھتا ہوں ایک عظیم الشان خوش خبری ہے کہ مدتوں تک
نسلاً بعد نسل جماعت احمد یہ سچائی پر قائم رہے گی اور یہ بھی بتادیا گیا کہ اگر تم دنیا کو اپنے قدموں
کے نیچے دیکھنا چاہتے ہو تو دنیا تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی سچائی کے قدموں کے
نیچے آئے گی.اس لئے تمہارے قدم بھی اگر اسی سچائی پر ہوں گے تو تب دنیا تمہارے قدموں
کے نیچے آئے گی ورنہ نہیں آئے گی.تو ادنی خواہشات دنیا کی رکھنے والے جو دنیا کی فتوحات پر
راضی ہونا چاہتے ہیں ان کو بھی باندھ کر ، ان کو بھی مقید کر کے سچائی کے قدموں پر لاکھڑا کیا
گیا.تمہیں بھی اگر فتوحات حاصل ہوئی ہیں تو اسی طرح فتوحات حاصل ہوئی ہیں کیونکہ آئندہ دنیا
کا نقشہ اسی طرح کھینچا گیا ہے.آئندہ دنیا مقدر اسی طرح تعمیر ہوگا کہ وہ حضرت مسیح موعود
1049
Page 1058
علیہ الصلوۃ والسلام کی سچائی کے تحت اقدام آئے.فرمایا:
اور قریب ہے کہ میں ایک عظیم الشان فتح پاؤں کیونکہ میری زبان کی تائید میں ایک اور
زبان بول رہی ہے اور میرے ہاتھ کی تقویت کے لئے ایک اور ہاتھ چل رہا ہے جس کو دنیا نہیں
دیکھتی مگر میں دیکھ رہا ہوں.میرے اندر ایک آسمانی روح بول رہی ہے جو میرے لفظ لفظ
اور حرف حرف کو زندگی بخشتی ہے.اور آسمان پر ایک جوش اور ابال پیدا ہوا ہے جس نے ایک
پتلی کی طرح اس مُشتِ خاک کو کھڑا کر دیا ہے.ہر ایک وہ شخص جس پر تو بہ کا دروازہ بند نہیں
عنقریب دیکھ لے گا کہ میں اپنی طرف سے نہیں ہوں.کیا وہ آنکھیں بینا ہیں جو صادق کو
شناخت نہیں کر سکتیں.کیا وہ بھی زندہ ہے جس کو اس آسمانی صدا کا احساس نہیں“.ازالہ اوہام روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 403)
حضرت رسول اکرم صلی لفظ فتح کو ایک اور عظیم الشان رنگ میں بھی استعمال فرماتے
ہیں.حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت امام نے فرما یا مَنْ فُتِحَ لَهُ مِنْكُمْ
بَابُ الدُّعَاءِ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ.(ترمذى - كتاب الدعوات حدیث نمبر 3471)
کہ تم میں سے جس پر دعا کا دروازہ کھول دیا گیا اس کے لئے رحمت کے دروازے کھول دئے
گئے.پس فتح کا اس سے بہتر تصور نہیں باندھا جاسکتا.(خطبہ جمعہ حضرت خلیفہ اسیح الرابع رحمہ اللہ ، فرمودہ 11 را پریل 1986 ء.خطبات طاہر جلد پنجم صفحہ 273 تا283)
1050
Page 1059
بسمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
تَبَّتْ يَدَا أَبِيْ لَهَبٍ وَتَبَّة
مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَتْ
سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ
وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ
فِي جِيْدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَّسَدةً
سورة اللهب
1 - ( میں ) اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا
( اور ) بار بار رحم کرنے والا ہے ( پڑھتا ہوں )
2.شعلہ کے باپ کے دونوں ہاتھ ہی شل ہو گئے
ہیں اور وہ (خود) بھی شل ہو کر رہ گیا ہے.3.اس کے مال نے اسے کوئی فائدہ نہیں دیا اور
نہ اس کی کوششوں نے (کوئی فائدہ ) دیا ہے.4.وہ ضرور آگ میں پڑے گاجو ( اسی کی طرح) شعلے
مارنے والی ہوگی.5.اور اس کی بیوی بھی جو ایندھن اٹھا اٹھا کر لاتی
ہے (آگ میں پڑے گی )
6.اس کی بیوی کی ) گردن میں کھجور کا سخت بٹا ہوا
رستا باندھا جائے گا.1051
Page 1060
تبت يدا أبي لهب وتب.حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں:
ابولہب کے ہاتھ ہلاک ہو گئے اور وہ بھی بلاک ہوگیا....ابولہب سے مراد وہ شخص
ہے جس نے فتنہ کی آگ کو مسلمانوں میں بھڑ کا یا اور اہلِ اسلام کو کافر قرار دیا اور عیسائیوں کی
تائید کی.پس چونکہ اس کا کام آگ بھڑکانا اور مسلمانوں کو دھوکا میں ڈالنا تھا اسی لئے اس کا نام
ابولہب ہوا.کیونکہ لھب زبانہ آتش کو کہتے ہیں اور لسان عرب میں ایک چیز کے موجد کو اس کا
باپ قرار دے دیتے ہیں.پس چونکہ فتنہ کی آتش کا زبانہ اس شخص سے پیدا ہوا ہے جس کا
پیشگوئی میں ذکر ہے اس لئے وہ اس زبانہ آتش کا باپ ہوا اور ابولہب کہلایا اور جہاں تک
میں سمجھتا ہوں اس جگہ ابو لہب سے مراد شیخ محمد حسین بٹالوی ہے واللہ اعلم.کیونکہ اس نے
کوشش کی کہ فتنہ کو بھڑ کاوے.( ضیاء الحق ، روحانی خزائن جلد 9 صفحہ 293 294)
تبتُ يَدَا أَبِي لَهَبٍ و تب کے الفاظ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو الہام بھی
ہوئے.چنانچہ آپ فرماتے ہیں:
بلاک ہو گئے دونوں ہاتھ ابی لہب کے (جبکہ اس نے یہ فتویٰ لکھا ) اور وہ آپ بھی
بلاک ہوگیا....اس الہام میں سورۃ مثبت کی پہلی آیت کا مصداق اس شخص کو ٹھہرایا ہے جس
نے سب سے پہلے خدا کے مسیح موعود پر تکفیر اور تو بین کے ساتھ حملہ کیا.اور یہ دلیل اس بات پر
ہے کہ قرآن شریف نے بھی اسی سورت میں ابولہب کے ذکر میں علاوہ دشمن رسول
اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کے مسیح موعود کے دشمن کو بھی مرادلیا ہے اور یہ تفسیر اس الہام کے ذریعہ سے کھلی ہے.اس لئے یہ تفسیر سراسر حقانی ہے اور تکلف اور تصنع سے پاک ہے.....غرض آیت
تبت يدا أبي لهب و تب جو قرآن شریف کے آخر سپارہ میں چار آخری سورتوں میں سے پہلی......1052
Page 1061
سورت ہے جس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے موذی دشمنوں پر دلالت کرتی ہے ایسا ہی
بطور اشارۃ النص اسلام کے مسیح موعود کے ایذا دہندہ دشمنوں پر اس کی دلالت ہے..خلاصہ کلام یہ ہے کہ تبت يدا أبي لَهَبٍ جو قرآن شریف کے آخر میں ہے آیت مَغْضُوبِ
علیہم کی ایک شرح ہے جو قرآن شریف کے اول میں ہے کیونکہ قرآن شریف کے
بعض حصے بعض کی تشریح ہیں.(تحفہ گولڑ و یه ، روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 215 تا 217)
سورة تبت کی پہلی آیت یعنی تبت يدا أبي لَهَبٍ و تب اس موذی کی طرف اشارہ
کرتی ہے جو مظہر جمال احمدی یعنی احمد مہدی کا مکفر اور مکذب اور مہین ہوگا.تحفہ گولڑو یہ، روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 214، 215)
وعاغَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ہے جس سے مراد وہ لوگ ہیں جو مسیح موعود کو دکھ دیں گے
اور اس دعا کے مقابل پر قرآن شریف کے اخیر میں سورة تبت یدا ابی لَهَبٍ ہے.(تحفہ گولڑ و بیه، روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 218)
ماضی مضارع کے معنوں پر بھی آجاتی ہے بلکہ ایسے مقامات میں جب کہ آنے والا
واقعہ متکلم کی نگاہ میں یقینی الوقوع ہو مضارع کو ماضی کے صیغہ پر لاتے ہیں تا اس امر کا
یقینی الوقوع ہونا ظاہر ہو اور قرآن شریف میں اس کی بہت نظیریں ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا
ہے...تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وتَبَّ -
( براہین احمدیہ حصہ پنجم، روحانی خزائن جلد 21 صفحہ 159)
خدا تعالیٰ نے جابجا قرآن شریف میں عظیم الشان پیشگوئیوں کو ماضی کے لفظ سے
بیان کیا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وتَبَّ -
( براہین احمدیہ حصہ پنجم، روحانی خزائن جلد 21 صفحہ 170)
سورة تَبَّتْ میں غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ کے فتنہ کی طرف اشارہ ہے.الحکم جلد 6 نمبر 8 مورخہ 28 فروری 1902 ، صفحہ 4)
( تبت يدا أبي لهب خواب میں پڑھنے کی تعبیر کے متعلق فرمایا )
1053
Page 1062
کسی دشمن پر فتح ہوگی
وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطب.( البدر جلد اول نمبر 11 مورخہ 9 جنوری 1903 صفحہ 84)
ابولہب قرآن کریم میں عام ہے، نہ خاص.مراد وہ شخص ہے جس میں التہاب واشتعال
کا مادہ ہو.اس طرح عمالة الخطب ہیزم کش عورت سے مراد ہے جو سخن چین ہو، آگ
لگانے والی.چغل خور عورت آدمیوں میں شرارت کو بڑھاتی ہے.سعدی کہتا ہے.سخن چین بدبخت هیزم کش است
حضرت خلیفہ المسیح الاول رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں :
الحکم جلد 2 نمبر 2 مورخہ 6 مارچ1898 صفحہ 2)
اس سورۃ شریف کا نام سورۃ تبت ہے.اور اس کو سورۃ لھب بھی کہتے ہیں.یہ سورت
مکہ معظمہ میں اتری ہے.ملا آبی لھب.کفار مکہ کے اکابر میں سے ایک شخص تھا.رشتہ میں آنحضرت سلیم کا چا
تھا.ابولہب اس کی کنیت تھی اور اس کا نام عبد العزہ ہی تھا.عرب میں ہر شخص کو بہ سبب عزت
کے کنیت سے بلاتے تھے.اور اصل نام کی بجائے اکثر لوگ کنیت کے ساتھ زیادہ معروف
ہوتے تھے.لھب کے معنے ہیں شعلہ.اور اب کے معنے باپ.آپی لھب کے معنے ہوئے
شعلہ کا باپ.بعض کا قول ہے کہ اس نے تکبر کے طور پر اپنے لئے یہ کنیت پسند کی تھی.ابولہب
اس واسطے بھی اسے کہتے تھے کہ اس کا چہرہ بہت سرخ تھا.شخص آنحضرت علی کے ساتھ نہایت عداوت رکھتا تھا.اور عداوت کی وجہ سوائے اس
کے نہ تھی کہ آنحضرت عمیل یا کلمہ توحید کا وعظ فرماتے تھے.اور یہ بت پرست تھا.رات دن
حضرت کو تکلیف دینے کے درپے رہتا تھا.جو لوگ باہر سے آتے اور آنحضرت میام کو ملنا
چاہتے ان کو آگے جا کر راستہ ہی میں ملتا اور بڑے تکلف اور تکبر کے ساتھ باتیں کرتا ہوا ان کو
1054
Page 1063
سمجھاتا کہ دیکھو محمد علی مجنون ہے.ہم اس کے چچا ہیں.وہ ہمارا بیٹا ہی ہے.ہم اس
کا علاج کر رہے ہیں.تم اس کے پاس مت جاؤ.بعض کو کہتا کہ محمد ( ال ) پر کسی نے جادو
کیا ہوا ہے.ایسے جادوزدہ شخص کے پاس جا کر تم کیا لو گے.بہتر ہے کہ یہیں سے واپس چلے
جاؤ.چنانچہ اس طرح کی باتیں بنا بنا کر لوگوں کو واپس کرنے کی کوشش کرتا رہتا.بعض
بدقسمت اس کا کہنا مان لیتے اور واپس چلے جاتے.اور جو لوگ زیادہ ہوشیار ہوتے وہ کہتے کہ ہم
تو اس کو ملنے کے واسطے آئے ہیں.کچھ ہی ہو اب تو ملاقات کر کے ہی جائیں گے.ایسے
لوگوں پر خفاہوتا اور پھر جھنجھلا کر آنحضرت علایم کو گالیاں دیتا.اور بعض کے کانوں میں روئی
ڈال دیتا کہ اچھا تم ضرور جانا چاہتے ہو تو جاؤ مگر اس کی باتیں نہ سننا کیونکہ اس کی باتوں میں ایک
جادو ہے وہ تم پر اثر کر جائے گا تو تم بھی اس کے ساتھ شامل ہو جاؤ گے.چنانچہ ایک صحابی کے
ساتھ ایسا ہی کیا اور اس کے ساتھ ایک آدمی بھی لگایا کہ جلد اس کو واپس لے آنا.زیادہ دیر تک
وہاں بیٹھنے نہ دینا.ورنہ ( نعوذ باللہ ) خراب ہو جائے گا.مگر وہ خدا کا بندہ ہوشیار آدمی تھا.اس
نے تھوڑی دور جا کر اس آدمی کو واپس کر دیا کہ تم جاؤ.میں خود اپنا راستہ تلاش کرلوں گا.اور روٹی
کو کانوں میں سے نکال کر پھینک دیا.ربیعہ بن عباد سے روایت ہے وہ کہتا ہے میں نے ایک
دفعہ حضرت رسول کریم عالم کو ابتدائے زمانہ رسالت میں دیکھا کہ آپ سوق المجاز میں کہہ
رہے تھے.اے لوگو ! لا إلهَ إِلَّا الله کہو تو تم اپنی مراد کو پہنچ جاؤ گے.بہت سے لوگ آپ
کے پاس جمع تھے.اور آپ کا وعظ سن رہے تھے.آپ کے پیچھے ایک شخص سرخ چہرہ والا اور
اخول لوگوں کو بہکاتا تھا کہ یہ شخص صابی ہے اور جھوٹ بولتا ہے.جدھر آنحضرت علایم
جاتے وہ بھی آپ کے پیچھے پیچھے جاتا اور لوگوں کو بہکاتا کہ یہ شخص تم کو لات اور غنی کی عبادت
سے منع کرتا ہے اس کے پیچھے مت جاؤ اور اس کی پیروی نہ کرو.میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ
شخص کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ آنحضرت ملالہ کا اچھا ہے.ایک دفعہ کا ذکر ہے.آنحضرت علیم نے اس کو تبلیغ کی تو اس نے سختی سے انکار کیا.تب آپ نے خیال کیا کہ یہ
متکبر آدمی ہے.لوگوں کے سامنے اس کو سمجھانا مفید نہیں پڑتا.شاید اس کو علیحدگی
1055
Page 1064
میں سمجھایا جاوے تو ہدایت کی راہ پر آجاوے اور جہنم میں گرنے سے بیچ رہے.اس واسطے آپ
رات کے وقت اس کے مکان پر گئے اور ایسا کرنے میں آپ نے حضرت نوح علیہ السلام کی
سنت کو ادا کیا.کیونکہ حضرت نوح نے کہا تھا اِلٰی دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا (نوح 6) میں
نے رات کے وقت بھی انہیں تبلیغ کی اور حق کی طرف بلایا اور دن کو بھی بلایا.جب آنحضرت
اس کے مکان پر پہنچے تو کہنے لگا کہ شاید آپ نے دن کے وقت جو کچھ کہا تھا اس کے متعلق
عذر کرنے کے لئے اس وقت آئے ہیں.پس رسول
کریم ملی اس کے سامنے ادب سے
بیٹھے رہے اور اسے اسلام کی طرف بہت تبلیغ کی.پر اس پر کچھ اثر نہ ہوا.حضرت ابن عباس
سے روایت ہے کہ رسول کریم ملایم ابتدائے زمانہ بعثت میں تبلیغ عام طور پر نہ کرتے
تھے.یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی وَ انْذِرُ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ (الشعراء 215).اپنے
قریبی قبائل کو آنے والے عذاب سے ڈراؤ.تب آپ کوہِ صفا پر چڑھ گئے اور پکارا.اے آل غالب.تب قبیلہ غالب کے لوگ جمع ہو گئے.اور ابولہب نے کہا.لے آل غالب
آگئے.اب بتا تیرے پاس کیا ہے.تب آپ نے پکارا یا آل لوٹی.اس وقت قبیلہ کوئی جمع
ہوا.پھر ابو لہب نے وہی کلمات کہے.تب آپ نے آلِ مُرہ کو پکارا.اسی طرح پھر آل کلاب
اور آل قصی کو پکارا.ہر دفعہ ابو لہب ایسا ہی کہتا رہا.جب سب جمع ہو گئے.تب آپ نے فرمایا
إِنَّ اللهَ آمَرَنِي أَنْ أُنْذِرَ عَشِيرَتِي الْأَقْرَبِينَ وَانْتُمُ الْأَقْرَبُونَ اعْلَمُوا أَنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ
الدُّنْيَا حَظًّا وَلَا مِنَ الْآخِرَةِ نَصِيبًا إِلَّا أَن تَقُولُو الا إِلَهَ إِلَّا اللهُ فَأَشْهَدُ بِهَالَكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ -
اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنے قبائل کو ڈراؤں.سو تم میرے قریبی ہو.تم یا درکھو کہ
میں نہ دنیا میں تمہیں کچھ فائدہ پہنچا سکتا ہوں.نہ آخرت سے
تمہیں کچھ حصہ دلا سکتا ہوں جب
تک
کہ تم اس بات پر ایمان نہ لاؤ کہ معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں.اگر تم میرا یہ
کہنا مان لو تو اللہ تعالیٰ کے حضور اس معاملہ میں میں تمہارے حق میں شہادت دوں گا.ابولہب
نے یہ کلمہ سن کر کہا.تَبالَك أَلِهَذَا دَعَوْتَنا تجھ پر ہلاکت ہو.کیا اس وسطے تُو نے ہم کو پکارا
تھا.اس کے بعد آنحضرت عالم پر یہ سورۃ نازل ہوئی اور وہی ہلاکت کی بددعا جو ابولہب نے
1056
Page 1065
آنحضرت علی ایم کے حق میں کی تھی اُلٹ کر خود اُسی پر پڑی.یہ ایک مباہلہ تھا جو کہ
آنحضرت علی کے ساتھ اس کا فر نے کیا تھا اور اس قسم کے مباہلوں کی مثالیں خود اس زمانہ
میں بھی قائم ہو چکی ہیں.اس سورۃ شریف میں کفار کے سرداروں میں سے ایک کو لیا گیا اور نام ذکر کیا گیا ہے.مگر دراصل اس میں تمام کفار کے سرداروں کی ہلاکت کی طرف اشارہ ہے جو آنحضرت علایم
کے بالمقابل کھڑے ہوئے تھے.اور آپ کی مخالفت میں ایک دوسرے سے بڑھ کر ہاتھ
بڑھاتے تھے.خدا تعالیٰ نے ان سب کو ہلاک کیا اور دین و دنیا میں خائب و خاسر کر دیا.(ماخوذ از حقائق الفرقان - زیر سورة اللهب )
حضرت خلیفہ المسیح الثانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
حمد سورۃ اللہب مکی سورۃ ہے.مضمون کے اعتبار سے سورۃ اللہب قرآن کریم کی آخری سورۃ ہے.کیونکہ ہماری ترتیب
کے لحاظ سے اس پر قرآن کریم کا مضمون ختم ہو جاتا ہے.اس کے بعد کی تین سورتوں میں قرآن
کریم کا خلاصہ بیان کر دیا گیا ہے.اس سورۃ کا پہلی سورۃ سے تعلق ہے کہ پہلی سورۃ میں رسول کریم عالم کو تسلی دی گئی
تھی کہ وہ فتوحات جو آپ کو ہورہی ہیں وہ آپ کی حیات تک محدود نہیں بلکہ ان فتوحات کے
دروازے آپ کی وفات کے بعد بھی کھلے رہیں گے.یہاں تک کہ اسلام دنیا پر غالب
آجائے گا.اور پھر یہ بھی بیان کیا گیا تھا کہ جب اسلام کو کسی ایسے شخص کی ضرورت ہوگی جو
اس کی کشتی کو بھنور سے نکالے اور اس کا جھنڈ اسرنگوں نہ ہونے دے.اللہ تعالیٰ اُس وقت کسی
ایسے شخص کو کھڑا کر دے گا اور امت محمدیہ علیم کی دستگیری فرمائے گا.م سورۃ لہب میں سورۃ نصر کے مضمون کو مکمل کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ صرف یہی
نہیں ہوگا کہ رسول کریم علیم کی وفات کے بعد فتوحات کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے
1057
Page 1066
اور اسلام غالب ہو جائے گا.بلکہ اگر کسی نے اسلام کومٹانے کے لئے اس پر حملہ کیا تو
اللہ تعالیٰ اس حملہ آور کو تباہ کر دے گا.نہ صرف اس کو بلکہ ان کو بھی جو اس حملہ آور کی تائید میں
ہوں گے.ایسے لوگ جو اسلام کے خلاف حملہ آور ہونے والے تھے ان کو اس سورۃ میں ابولہب کے
نام سے پکارا ہے.اور ان کو جو ایسے لوگوں کی تائید میں ہوں گے.بیوی کے لفظ سے تعبیر کیا
ہے.گویا ابولہب سے مراد ائمہ کفر ہیں اور اس کی بیوی سے مراد اُن کے اتباع.اس سورۃ کا تعلق سورۃ کوثر سے بھی ہے.سورۃ کوثر میں رسول کریم لالا لال لال سے دو
وعدے کئے گئے تھے.(1) کثرت جماعت کا وعدہ.(2) دشمنوں کی تباہی کا وعدہ.گویا پہلے
وعدہ کے پورا ہونے کا ذکر سورۃ نصر میں کیا گیا ہے اور دوسرے وعدے کے پورا ہونے کا ذکر
سورۃ لہب میں ہے.اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ کو بالکل ابتدائی زمانہ میں نازل فرما کر مسلمانوں کی ہمت بندھائی
کہ گھبراؤ نہیں گو تم کمزور اور ضعیف ہو لیکن تمہارا مددگار وہ طاقتور خدا ہے کہ جس کے منشاء کے
ماتحت زمین و آسمان کے ذرات حرکت میں آتے ہیں.پس جو بھی تمہاری مخالفت کرے گا وہ
رُسوا و خوار ہوگا اور تباہی کا منہ دیکھے گا.پھر مضمون کے اعتبار سے اس سورۃ کو بالکل آخر میں رکھا.تا آئندہ آنے والی نسلوں کے حوصلے بلند ہوں اور کسی زمانہ میں کفر کی طاقت کو دیکھ کر مسلمان گھبرا
نہ جائیں.بلکہ یہ یقین رکھیں کہ اسلام کا خدا غالب خدا ہے اور وہ اس کے دشمنوں کو خود تباہ کر دے
گا.گویا سورۃ نصر اور سورۃ لہب امت کے نام دو آخری پیغام ہیں.ایک زیادتی ایمان اور ترقی
ایمان کی طرف لے جاتا ہے اور دوسرا کفر کی ہلاکت کی طرف ذہن کو منتقل کرتا ہے.اس سورۃ میں یہ بتایا گیا ہے کہ ابولہب کے نام کی مستحق اقوام جو آخری زمانہ میں پیدا
ہوں گی.اللہ تعالیٰ اُن کو اور اُن کے ساتھیوں کو نا کام کر دے گا.ا اس کے بعد فرماتا ہے کہ علاوہ غیر قوموں کے جو کہ بطور ہاتھ کے ہیں.خود ان ملکوں میں
بھی ایسے گروہ پائے جائیں گے جو کہ خدا تعالیٰ اور محمد رسول اللہ علی ایم کے خلاف جنگ کرنے
1058
Page 1067
کے لئے اپنی حکومتوں کو بھڑکائیں گے.صاف ظاہر ہے کہ ایسے گروہ مغربی ممالک میں بھی
موجود ہیں اور مشرقی ممالک میں بھی موجود ہیں.ان گروہوں کا نام اس مناسبت سے کہ وہ
اندرونی ہیں.امر آنا رکھا گیا ہے یعنی بیوی.اور فرماتا ہے کہ ابولہب کی بیوی بھی تباہ ہو جائے
گی.یعنی ان قوموں کے وہ گروہ بھی کمزور ہو جائیں گے اور نقصان اٹھائیں گے جو لکڑیاں ڈال
ڈال کر حکومت کی آگ کی طاقت کو بڑھا رہے ہیں.لکڑیاں ڈالنے سے اس جگہ مراد یہ ہے کہ
وہ حکومت کو شہ دلاتے ہیں کہ تم ایسے کام کرو.جیسا کہ مغربی ممالک میں ایسے لوگ موجود ہیں جو
کہ اسلام کے خلاف لٹریچر لکھواتے ہیں اور اسرائیل کی تائید کے لئے ان ممالک کو اکساتے
رہتے ہیں.اسی طرح مشرق میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنی قوم کو اور اپنی حکومت کو دہریت کی
تائید میں اکساتے رہتے ہیں اور توحید کے خلاف جنگ پر آمادہ کرتے رہتے ہیں.اس سورۃ سے پتہ لگتا ہے کہ آخر اللہ تعالیٰ اِن دونوں فتنوں کو دور کر دے گا.نہ مغربی
جمہوریت کے اشتعال پسند لوگ محفوظ رہیں گے.نہ اس کے مقابل کی مشرقی طاقت کے
اشتعال پسند لوگ محفوظ رہیں گے.پھر فرماتا ہے کہ باوجود بچنے کی ساری تدبیروں کے ان کو کسی جنگ میں مبتلا ہونا پڑے
گا جو بڑی شعلوں والی ہوگی.اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے.اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شاید کسی وقت
ایٹم بم اور ہائیڈ روجن بم کی جنگ ہو جائے گی.لیکن اللہ تعالیٰ چاہے تو جیسا کہ قرآن شریف کی
آیات سے پتہ لگتا ہے، عذاب ٹل بھی جایا کرتے ہیں.اگر یہ لوگ استغفار سے کام لیں تو یہ
عذاب ٹل بھی سکتا ہے.ضروری نہیں کہ اسی شکل میں آئے.ممکن ہے کہ ایٹم بم کی جگہ اصولوں
کی مخالفت اور مقابلہ کی صورت میں ہی پیشگوئی پوری ہو جائے.تبت يدا أبي لَهَبٍ وتَب
الید کے معنے ہیں الگف.ہاتھ.نیز اس کے معنے ہیں الْجَاهُ وَالْوَقَارُ.عزت ورتبہ.الْقُوَّةُ وَالْقُدْرَةُ وَالسُّلْطنُ وَالْوَلَايَةُ ـ قوت و طاقت.بادشاہت اور غلبہ - الْجَمَاعَةُ -
1059
Page 1068
جماعت النَّعْمَةُ وَالْإِحْسَانُ احسان اور نعمت.( اقرب)
الآب: الَّذِى يَتَوَلَّدُ مِنْهُ أَخَرُ مِنْ نَوْعِهِ.یعنی اس وجود کو جس سے اسی نوع کی چیز
پیدا ہوجس نوع کا وہ خود ہے آب کہتے ہیں.یعنی والد.نیز آب کے معنے ہیں مَن كَانَ سَبَبًا في
الْجَادِ شَيْءٍ أو اضلاحه او ظهورہ جو کوئی کسی چیز کے ایجاد کرنے یا ظاہر کرنے اور وجود میں
لانے کا سبب ہو اس کو بھی آب کہتے ہیں.(اقرب)
الهب: لَهَب لھب کا مصدر بھی ہے اور اسم بھی ہے.لھبَتِ النَّارُ کے معنے ہوتے
ہیں اشْتَعَلَتْ خَالِصَةً مِّنَ الدُّخَانِ آگ ایسی تیزی سے بھڑک اٹھی کہ اس میں دھواں باقی
نہ رہا.اور اللهَبُ کے معنے ہوتے ہیں.لِسانُ النَّارِ یعنی آگ کا شعلہ.( اقرب)
پس ابو لہب کے معنے ہوں گے شعلوں کا باپ.یعنی ایسی چیزوں کا موجد جو آگ کو
بھڑ کا ئیں.وہ
حمد احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جب دجال اور یاجوج و ماجوج کے فتنے برپا ہوں گے
اور اسلام کمزور ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ اسلام کی حفاظت کے لئے مسیح موعود کو نازل کرے گا اور
مشرق میں ظاہر ہوگا اور اس کے آنے کے بعد وجبال بلاک ہو جائے گا.اس وقت مسلمانوں
کے پاس مادی طاقت نہ ہوگی.لیکن مسیح موعود کی جماعت دعاؤں اور تبلیغ کے ساتھ کام کرتی چلی
جائے گی اور یا جوج و ماجوج آسمانی عذابوں کے ساتھ تباہ ہوں گے اور اللہ تعالیٰ پھر اسلام کو
غالب کر دے گا اور وہ دنیا کو کہے گا کہ تیری برکت تجھ میں پھر لوٹ آئے اور تھوڑا رزق لوگوں
کے لئے کافی ہوگا.حرص مٹ جائے گی اور لوگ مادیت کی بجائے روحانیت کی طرف مائل
ہو جائیں گے یہاں تک کہ اسلام غالب ہو جائے گا.الغرض اسلام کو مٹانے کے لئے جو خطرناک فتنے آخری زمانے میں پیدا ہونے
والے تھے سورہ لہب میں اللہ تعالیٰ نے اُن کے متعلق اور اُن کے انجام کے متعلق پیشگوئی
فرمائی ہے اور کہا ہے تبت یدا ابی لَهَبٍ وتب.یعنی اسلام کے خلاف آگ بھڑ کانے والی
1060
Page 1069
اقوام جو آخری زمانہ میں پیدا ہوں گی اللہ تعالیٰ اُن کو اور اُن کے ساتھیوں کو تباہ کرے گا.اتب کے معنے برباد ہونے اور بلاک ہونے کے ہیں.اور جب کسی کا مقصد حاصل نہ
ہو.اس وقت بھی تب کا لفظ استعمال کرتے ہیں.مفسرین نے تبت کے معنے صَفِرَتْ مِنْ
كل خیر کے بھی کئے ہیں.یعنی ہر قسم کی خیر و برکت سے خالی رہنا.دید کے معنے ہاتھ کے بھی ہیں اور عزت ورتبہ.قوت و طاقت اور غلبہ و بادشاہت کے بھی
ہیں.اسی طرح کیک کا لفظ جماعت پر بھی بولا جاتا ہے.پس تبت یدا ابی لَهَبٍ کے معنے
ہوں گے.1.ابولہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو گئے.2.ابولہب کے دونوں جتھے برباد ہو گئے اور ان کو اُن کا مقصد حاصل نہ ہوا.3.ابولہب کی عزتیں ، قو تیں، بادشاہت اور غلبہ سب ختم ہو گئے.4.ابولہب کے ساتھ تعلق رکھنے والی دونوں جماعتیں ہر قسم کے نفع اور خیر سے محروم رہیں.ابولہب کے لفظی معنے ہیں شعلے کا باپ.لیکن محاورے میں اس کے معنے ہوں گے وہ وجود
جو ایسی چیزوں کا موجد ہو جن سے شعلے اور آگ پیدا ہو.یاوہ وجود جس کا انجام یہ ہوگا کہ وہ شعلوں
کی لپیٹ میں آجائے گا.مفسرین کہتے ہیں کہ لفظ ابو لہب سے چہرے کا سرخ و سفید رنگ بھی
مراد ہوسکتا ہے.علی سورۃ مثبت میں ابولہب سے مراد کوئی ایک شخص نہیں بلکہ اس سے مراد وہ قوم ہے جو
آخری زمانہ میں دنیا پر غلبہ حاصل کر کے رسول کریم علی ایم کے خلاف یا اسلام کے خلاف
آگ بھڑکائے گی.یا وہ ایسی ایجادیں کرے گی جس سے شعلے اور آگ پیدا ہو.اور پھر یہ قوم
اپنی ہمسایہ قوموں کو بھی اپنے ساتھ ملا کر اپنے جتھہ کو مضبوط کرے گی اور یہ قومیں اس کے ہاتھ کی
مانند ہوں گی.ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانہ میں دو ہی جتھے ایسے ہیں جو کہ اسلام یا رسول کریم علیم کے
خلاف متحد ہیں.ایک جتھے بعض مغربی طاقتوں پر مشتمل ہے اور ایک جتھے بعض مشرقی طاقتوں
1061
Page 1070
اور ان کے ساتھیوں کا ہے.ابولہب سے مراد یہ دونوں جتھے ہیں.یہ ظاہر میں بھی ابولہب ہیں کہ
ان کے رنگ سرخ و سفید ہیں اور باطن کے لحاظ سے بھی کہ ایٹم بم اور ہائیڈ روجن بم ایجاد کر
رہے ہیں جن کا نتیجہ آگ اور شعلے ہیں.اور اس لحاظ سے بھی ابولہب ہیں کہ یہ انجام کار جنگ کی
آگ کی لپیٹ میں آنے والے ہیں اور چونکہ ان لوگوں نے محمد رسول اللہ صلیم کے خلاف
خطرناک لٹریچر پیدا کر کے ایک آگ لگادی ہے اس لئے بھی وہ ابولہب کہلانے کے مستحق
ہیں.تبت يَدَا بِي لَهَبٍ میں تبت ماضی کا صیغہ استعمال ہوا ہے.لیکن عربی زبان میں جب
کوئی امر یقینی اور قطعی طور پر ہونے والا ہو تو اس کے لئے ماضی کا صیغہ استعمال کرتے ہیں.گویا
یہ بتایا جاتا ہے کہ تم یہ سمجھو کہ یہ کام ہو چکا.پس تبت کے معنے اس جگہ پر یہ ہوں گے کہ یہ یقینی
بات ہے کہ یہ تباہ ہو جائیں گے اور اُن کا مقصد کہ اسلام کو مٹادیں حاصل نہ ہوگا.پھر یہ امر بھی قابل غور ہے کہ آیت زیر تفسیر میں پہلے ابولہب کے دونوں ہاتھوں کی تباہی
کا ذکر ہے اور پھر اس کی اپنی تباہی کا.اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ابولہب کا نام پانے والی
اقوام یعنی مشرقی اور مغربی طاقتیں دونوں پوری کوشش کریں گی کہ مختلف ممالک کو اپنے
ساتھ ملالیں اور وہ ممالک ان کے ساتھ مل بھی جائیں گے اور ان کے لئے بطور ہاتھوں کے ہو
جائیں گے.اور ابولہب کہلانے والی اقوام ان جتھوں پر فخر کریں گی اور ان کو اپنی طاقت شمار
کریں گی.لیکن اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کرے گا کہ پہلے تو یہ مؤیدین تباہ ہوں گے اور پھر وہ
وجود جو ابولہب کہلانے کا مستحق ہوگا اور ان قوموں کا نقطہ مرکزی ہوگا ، وہ تباہ ہوگا.ایک لطیف بات جو اس جگہ قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ احادیث میں جہاں اسلام کے
خلاف اُٹھنے والی تحریکات کو بیان کیا گیا ہے وہاں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان فتنوں کے وقت
اللہ تعالیٰ مسیح موعود کو نازل کرے گا اور وہ ان فتنوں کا مقابلہ کریں گے.لیکن دعاؤں سے.کیونکہ
لا يَدَانِ لِأَحَدٍ لِقِتَالِهِمْ.(مشكوة كتاب الفتن) ان اسلام کے مخالف لوگوں کا مقابلہ
مادی ہتھیاروں سے نہ ہو سکے گا.اس لئے کہ مسلمانوں کی حالت ضعف و کمزوری کی ہوگی لیکن
1062
Page 1071
اللہ تعالیٰ مسیح موعود علیہ السلام کی دعاؤں کو سنے گا اور ایسے سامان پیدا کر دے گا کہ جس طرح
نمک پانی میں گھل جاتا ہے اسی طرح یہ اسلام کی مخالف اقوام آپس میں لڑ کر تباہ ہوجائیں گی.قرآن کریم نے ابولہب کا نام پانے والی اقوام کے مؤیدین کو بھی ہاتھوں سے تعبیر کیا ہے
اور فرمایا ہے تبت یدا ابی لَهَبٍ اور حدیث میں بھی جہاں آخری زمانہ میں پیدا ہونے والے
فتنوں کا ذکر ہے وہاں یہ ان کا لفظ استعمال کیا گیا ہے.یہ امر بتا تا ہے کہ رسول کریم عالم کو
اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے متعلق آخری زمانہ میں آنے والے ابتلاؤں کا علم دے دیا تھا اور
بتا دیا تھا کہ سورۃ لہب میں جن اقوام کے خروج کی خبر دی گئی تھی اُن کا مقابلہ ظاہری طاقت
سے نہ ہو سکے گا.تبھی تو آپ نے فرما دیا کہ لا يَدَانِ لِأَحَدٍ لِقِتَالِهِمْ.الغرض آیت تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وتَب میں یہ پیشگوئی کی گئی ہے کہ اسلام پر حملہ کرنے
والی اقوام اور اس کی تائید میں اُٹھنے والے لوگ سب تباہی کا منہ دیکھیں گے اور اسلام کو مٹانہ
سکیں گے.مَا أَغْلَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ.پہلی آیت میں اس بات کا ذکر تھا کہ اسلام پر حملہ کرنے والی اقوام تباہ ہوں گی اور نہ
صرف خود تباہ ہوں گی بلکہ وہ لوگ جو اُن کے ساتھ اس لئے شامل ہوئے تھے کہ ان کو کچھ نفع ہوگا
وہ بھی حسرت کے ساتھ تباہ ہوں گے اور اُن کو اُن کا مقصد حاصل نہ ہوگا.م اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اقوام بڑی مالدار ہوں گی اور نہ صرف یہ کہ
انہوں نے ایجادوں اور صنعتوں سے بہت مال پیدا کیا ہوگا بلکہ اپنا راس المال دوسرے ملکوں
میں لگا کر اور تجارت کے بہانے دوسرے ملکوں پر قبضہ کر کے اُن ملکوں کا مال بھی اپنے قبضہ
میں کر لیا ہوگا.مالہ میں لفظ مال نکرہ رکھا اور نکرہ عظمت شان پر دلالت کرتا ہے.گویا اس سے
یہ اشارہ کیا کہ اس کا عظیم الشان مال بھی اس کو تباہی سے بچا نہ سکے گا.ماله كے بعد مَا كَسَب کے الفاظ رکھے ہیں اور مَا كَسَبَ کے معنے ہیں.مَكْسُوبُهُ.اس کا
1063
Page 1072
کمایا ہوا مال.گویا ان اقوام کے مالوں کو دوحصوں میں تقسیم کیا گیا ہے (1) وہ مال جو اپنے ملکوں
میں صنعتوں وغیرہ سے پیدا کریں گے.(2) وہ مال جو دوسرے ملکوں سے حاصل کریں گے.یہ ظاہر ہے کہ یہ آیت مغربی اقوام پر پوری طرح صادق آتی ہے کیونکہ ایک طرف صنعتی
ترقی سے وہ مالدار ہوگئی ہیں اور دوسری طرف انہوں نے نہ صرف دوسرے ملکوں میں اپنا
رأس المال لگا کر ان کا مال چھین لیا بلکہ اس بہانے سے انہوں نے کئی ملکوں پر بھی قبضہ کر لیا.ما اغلی عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ کے الفاظ بھی اس امر کی دلیل ہیں کہ سورۃ لہب کا نزول
عبدالعزیٰ کے لئے قرار دینا کسی طرح بھی درست نہیں کیونکہ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ کے الفاظ
مال کثیر کی طرف اشارہ کرتے ہیں.اور عبد العرہ ہی کے پاس تو کوئی ایسا مال نہ تھا جو قابل ذکر
ہو اور نہ وہ اپنے زمانہ میں مالدار سمجھا جاتا تھا.کسی کے پاس چند اونٹوں کا ہونا اس کو مالدار نہیں
بنا سکتا.پس مَالُهُ وَمَا كَسَب کے الفاظ اپنی پوری شان کے ساتھ مغربی اقوام پر ہی صادق
آتے ہیں کیونکہ یہی وہ اقوام ہیں جو دنیا کی دولتمند اقوام سمجھی جاتی ہیں.مفسرین کے نزدیک ما کسب سے مراد اعمال، کوششیں اور اولاد بھی ہوسکتی ہے.پس ان
معنوں کے اعتبار سے یہ مفہوم ہو گا کہ ان قوموں کو اپنے جتھوں، اپنے اموال اور اپنی ایجادات پر
بڑا نا ز ہوگا.لیکن تباہی کے وقت یہ چیزیں اُن کے کام نہیں آئیں گی بلکہ یہی چیزیں ان کی تباہی کا
موجب ہوجائیں گی.سَيَصْلى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ
نار کے معنے آگ کے ہیں اور نار سے مراد جنگ بھی ہوتی ہے.سَيَضلى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ کے معنے یہ ہوں گے کہ ابو ہی تحریکیں ایک سخت جنگ میں ڈالی
جائیں گی اور وہ ایسی جنگ ہوگی جو شعلوں والی ہوگی اور ایسی ہوگی جس کی مثال پہلے بلتی ہوگی.کیونکہ ناڑ نکرہ ہے اور نکرہ عظمت شان پر دلالت کرتا ہے.یہ ظاہر ہے کہ ایٹم بم اور ہائیڈ روجن
بم کا نتیجہ سوائے آگ کے شعلوں اور شدید گرمی کے کیا ہوسکتا ہے کیونکہ ان کے استعمال سے
بیک وقت شہروں کے شہر آگ کی لپیٹ میں آسکتے ہیں.1064
Page 1073
پس یہ آیت بتاتی ہے کہ ان اقوام کو ایک ہولناک جنگ کا سامنا کرنا پڑے گا.اور یہ
آپس میں لڑ کر تباہ ہو جائیں گی.عربی زبان میں تش اور سوف جب فعل پر داخل ہوتے ہیں تو
زمانہ کی مقدار بتاتے ہیں کہ یہ فعل کب واقع ہو گا.س زمانہ قریب کے لئے آتا ہے اور
سؤف زمانہ بعید کے لئے.اس آیت میں سیصلی فعل پرس داخل ہوا ہے جو زمانہ قریب
پر دلالت کرتا ہے گویا اس میں اشارہ کیا گیا ہے کہ یہ قو میں جو محمد رسول اللہ علیم کے خلاف
آگ بھڑ کا ئیں گی اور آپ کے مذہب کو تباہ کرنے کی کوشش کریں گی جس وقت اُن کی
کوششیں انتہا کو پہنچ جائیں گی تو اس کے بعد جلد ہی وہ لڑائی کی آگ میں جھونکی جائیں گی.چنانچہ دیکھ لو کہ مغربی تحریکیں اسلام کے خلاف 1914ء میں کمال کو پہنچیں اور اس کے معاً
بعد ان کی آپس میں جنگ ہو گئی جو 1918ء میں ختم ہوئی.اور پھر دوبارہ 1938ء میں اس
کے نتیجہ میں پھر ایک جنگ ہوئی جو 1945ء تک چلی گئی اور 1945ء کے بعد ایٹم بم اور
ہائیڈروجن بم کی ایجاد ہوئی جس سے دنیا ایک اور تباہی کے کنارہ پر کھڑی ہے اور یہ زمانہ اس
زمانہ کے بالکل قریب ہے جس میں ان مغربی اقوام کی کوششیں اسلام کے خلاف انتہا کو پہنچ
گئی تھیں.وَامْرَآتُه حَمالَةَ الْحَطب
حطب.الْحَطبُ مَا أُعِدَّ مِنَ الشَّجَرِ شَيُوبًا لِلنَّارِ.درخت کی لکڑیاں جو جلانے
کے لئے تیار کی جاتی ہیں اور خشک کی جاتی ہیں ان کو خطب کہتے ہیں.یعنی ایندھن.نیز
الخطب کے معنے ہیں النَّبِيمَةُ.چغلخوری.(اقرب)
والی.پس عمالة الخطب کے معنے ہوں گے (1) ایندھن اُٹھانے والی (2) چغلخوری کرنے
امراق کے معنے عورت کے ہیں.لیکن یہ لفظ ایسے لوگوں کے لئے بھی استعمال ہو جاتا
ہے جو کسی کے ماتحت ہوں اور قوت متاثرہ رکھتے ہوں....پس وَامْرَآتُه حَمَّا لَةَ الحطب
سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابولہب کے نام کی مستحق اقوام کے ساتھ نہ صرف یہ کہ اور لوگ بھی اپنے
1065
Page 1074
فائدے کے لئے شامل ہو جائیں گے جو اُن کے لئے بطور ہاتھ کے ہوں گے.بلکہ بعض ایسے
لوگ بھی اُن کے ساتھ ہوں گے جو اُن کے اپنے ملکوں میں ہوں گے.اور اپنی حکومتوں کو
شہ دلائیں گے کہ وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ایسے کام کریں جن سے اسلام ختم ہو جائے.یعنی لٹریچر بھی لکھوائیں گے اور اُن کے خلاف جنگ کے لئے بھی اُکسائیں گے.گویا ایندھن
بھی مہیا کریں گے اور اسلام کے خلاف چغلخوری بھی کریں گے اور غلط باتیں پیش کر کے
لوگوں کو اسلام کے خلاف بھڑکائیں گے.فِي جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ
في جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ کے معنے ہیں کہ وہ لوگ جو ابو سہی اقوام کے لئے بمنزلہ
عورت کے ہیں اُن کے گلوں میں ایسی رشیاں ہیں جو ٹوٹ نہیں سکتیں.یعنی ان کی مخالفت اسلام
کے خلاف اتنی شدید ہوگی کہ اس کو دور کرنا مشکل ہوگا.پھر اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ بظاہر ان حکومتوں کی قومیں آزاد کہلائیں گی لیکن
در حقیقت اپنے زمانہ کے رسم و رواج کی غلام ہوں گی اور جب تک خدا تعالیٰ ان کو آزاد نہ کرائے
وہ حقیقی آزادی حاصل نہیں کر سکیں گی.(ماخوذ از تفسير كبير زيرسورة اللهب )
1066
Page 1075
XXXXXXXXXX
بسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
قُلْ هُوَ اللهُ اَحَدٌ
اللهُ الصَّمَدُة
لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدُن
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدَّةً
سورة الاخلاص
XXX
1 - (میں) اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا
( اور ) بار بار رحم کرنے والا ہے ( پڑھتا ہوں )
2 ( ہم ہر زمانہ کے مسلمان کو حکم دیتے ہیں کہ ) تو
( دوسرے لوگوں سے ) کہتا چلا جا کہ (اصل) بات
یہ ہے کہ اللہ اپنی ذات میں اکیلا ہے.3.اللہ وہ ( ہستی ) ہے جس کے سب محتاج ہیں
( اور وہ کسی کا محتاج نہیں)
4.نہ اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ وہ جنا گیا ہے.5.اور اس کی صفات میں) اس کا کوئی بھی
شریک کار
نہیں.1067
Page 1076
قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ.لَمْ يَلِدُ.وَلَمْ يُولَدُ وَلَمْ يَكُن لَّهُ
كُفُوًا أَحَدٌ
حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں:
اس اقل عبارت کو جو بقدر ایک سطر بھی نہیں، دیکھنا چاہئے کہ کس لطافت اور عمدگی سے
ہر یک قسم کی شراکت سے وجود حضرت باری کا منز“ ہ ہونا بیان فرمایا ہے.اس کی تفصیل یہ
ہے کہ شرکت از روئے حصر عقلی چار قسم پر ہے.کبھی شرکت عدد میں ہوتی ہے اور کبھی مرتبہ
میں اور کبھی نسب میں اور کبھی فعل اور تاثیر میں.سو اس سورہ میں ان چاروں قسموں کی شرکت
سے خدا کا پاک ہونا بیان فرمایا اور کھول کر بتلا دیا کہ وہ اپنے عدد میں ایک ہے.دو یا تین
نہیں.اور وہ صمد ہے یعنی اپنے مرتبہ وجوب اور محتاج الیہ ہونے میں منفرد اور یگانہ ہے.اور بجز
اس کے تمام چیزیں ممکن الوجود اور بالک الذات ہیں جو اس کی طرف ہر دم محتاج ہیں.اور وہ
لم یلد ہے یعنی اس کا کوئی بیٹا نہیں تا بوجہ بیٹا ہونے کے اس کا شریک ٹھہر جائے.اور وہ
لَمْ يُولّد ہے یعنی اس کا کوئی باپ نہیں تا بوجہ باپ ہونے کے اس کا شریک بن جائے.اور
وه لَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا ہے یعنی اس کے کاموں میں کوئی اس سے برابری کرنے والا نہیں تا
باعتبار فعل کے اس کا شریک قرار پاوے.سو اس طور سے ظاہر فرما دیا کہ خدائے تعالیٰ
چاروں قسم کی شرکت سے پاک اور منزہ ہ ہے اور وحدہ لاشریک ہے.( براہین احمدیہ چہار حصص، روحانی خزائن جلد 1 صفحه 518 حاشیه در حاشیہ نمبر (3)
قرآن کریم کی صاف تعلیم یہ ہے کہ وہ خداوند وحید وحمید جو بالذات توحید کو چاہتا ہے
اس نے اپنی مخلوق کو منتشارک الصفات رکھا ہے اور بعض کو بعض کا مثیل اور شبیہ قرار دیا ہے تا
کسی فرد خاص کی کوئی خصوصیت جو ذات و افعال و اقوال اور صفات کے متعلق ہے اس دھوکہ
1068
Page 1077
میں نہ ڈالے کہ وہ فرد خاص اپنے بنی نوع سے بڑھ کر ایک ایسی خاصیت اپنے اندر رکھتا ہے کہ
کوئی دوسرا شخص نہ اصلاو نہ ظلاً اس کا شریک نہیں اور خدا تعالیٰ کی طرح کسی اپنی صفت میں
واحد لاشریک ہے.چنانچہ قرآن کریم میں سورۃ اخلاص اسی بھید کو بیان کر رہی ہے کہ
احدیت ذات وصفات خدا تعالیٰ کا خاصہ ہے.دیکھو اللہ جل شانہ فرماتا ہے قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ
( آئینہ کمالات اسلام، روحانی خزائن جلد 5 صفحه 44، 45)
لا وَلَا الضَّالِّين...کے مقابل پر قرآن شریف کے اخیر میں سورۃ اخلاص ہے.یعنی قلی
هُوَ اللهُ أَحَدُ اللهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدُ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ...وہ اہم مقصد جو قرآن میں مفصل بیان کیا گیا ہے سورہ فاتحہ میں بطور اجمال اس کا
افتتاح کیا ہے اور پھر سورۃ تبت اور سورۃ اخلاص اور سورۃ فلق اور سورۃ الناس میں ختم قرآن
کے وقت میں انہی دونوں بلاؤں سے خدا تعالی کی پناہ مانگی گئی ہے.پس افتتاح کتاب اللہ
بھی انہی دونوں دعاؤں سے ہوا اور پھر اختتام کتاب اللہ بھی انہی دونوں دعاؤں پر کیا گیا.( تحفہ گولڑویہ، روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 218)
قرآن نے اپنے اول میں بھی مغضوب علیہم اور ضالین کا ذکر فرمایا ہے اور اپنے آخر
میں بھی جیسا کہ آیت لَمْ يَلِدُ وَلَمْ يُولّد بصراحت اس پر دلالت کر رہی ہے اور یہ تمام اہتمام
تاکید کے لئے کیا گیا اور نیز اس لئے کہ تا مسیح موعود اور غلبہ نصرانیت کی پیشگوئی نظری نہ رہے
اور آفتاب کی طرح چمک اُٹھے.(تحفہ گولڑویہ، روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 222)
آخری مظہر شیطان کے اسم دجال کا جو مظہر اتم اور اکمل اور خاتم المظاہر ہے وہ قوم
ہے جس کا قرآن کے اول میں بھی ذکر ہے اور قرآن کے آخر میں بھی.یعنی وہ ضالین کا فرقہ جس
کے ذکر پر سورۃ فاتحہ ختم ہوتی ہے اور پھر قرآن شریف کی آخری تین سورتوں میں بھی اس کا ذکر
ہے یعنی سورہ اخلاص اور سورہ فلق اور سورہ ناس میں.صرف یہ فرق ہے کہ سورہ اخلاص میں تو
اس قوم کی اعتقادی حالت کا بیان ہے جیسا کہ فرمایا قُل هُوَ اللهُ أَحَدُ اللهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدُ.وَ
1069
Page 1078
لَمْ يُولَدُ.وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ یعنی خدا ایک ہے اور آحد ہے یعنی اس میں کوئی ترکیب
نہیں.نہ کوئی اس کا بیٹا اور نہ وہ کسی کا بیٹا اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے.پس اس سورت میں تو اس
قوم کے عقائد بتلائے گئے.(تحفہ گولر و بیه، روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 269 270 حاشیہ)
لا قُلْ هُوَ اللهُ اَحَدُ اللهُ الصَّمَدُ.کہ وہ معبود حقیقی جس کی طرف سب چیزیں عبودیتِ
تامہ کی فنا کے بعد یا قہری فنا کے بعد رجوع کرتی ہیں ایک ہے.باقی سب مخلوقات دو قسم فنا
میں سے کسی فنا کے نیچے ہیں اور سب چیزیں اس کی محتاج ہیں.وہ کسی کا محتاج نہیں.لعمھ بلڈ.وَلَمْ يُولَدُ.وہ ایسا ہے کہ نہ تو اس کا کوئی بیٹا ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے.وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا
آحد.اور ازل سے اس کا کوئی نظیر اور مثیل نہیں.یعنی وہ اپنی ذات میں نظیر اور مثیل
پاک اور منزہ ہ ہے.....دونوں سورتوں (اخلاص اور فلق ) میں ایک ہی فرقہ کا ذکر ہے صرف
فرق یہ ہے کہ سورۃ اخلاص میں اس فرقہ کی اعتقادی حالت کا بیان ہے اور سورۃ الفلق میں اس
فرقہ کی عملی حالت کا ذکر ہے.( تحفہ گولڑ و بیه، روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 270 ، 271 حاشیہ)
حمید قرآن میں ہمارا خدا اپنی خوبیوں کے بارے میں فرماتا ہے قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ اللهُ
الصَّمَدُ.لَمْ يَلِدُ.وَلَمْ يُولَدُ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا اَحَدُ.یعنی تمہارا خدا وہ خدا ہے جو اپنی
ذات اور صفات میں واحد ہے.نہ کوئی ذات اس کی ذات جیسی از لی اور ابدی یعنی انادی اور
اکال ہے نہ کسی چیز کے صفات اس کی صفات کی مانند ہیں.انسان کا علم کسی معلم کا محتاج ہے
اور پھر محدود ہے مگر اس کا علم کسی معلم کا محتاج نہیں اور بایں ہمہ غیر محدود ہے.انسان کی شنوائی
ہوا کی محتاج ہے اور محدود ہے مگر خدا کی شنوائی ذاتی طاقت سے ہے اور محدود نہیں.اور انسان
کی بینائی سورج یا کسی دوسری روشنی کی محتاج ہے اور پھر محدود ہے مگر خدا کی بینائی ذاتی روشنی
سے ہے اور غیر محدود ہے.ایسا ہی انسان کی پیدا کرنے کی قدرت کسی مادہ کی محتاج ہے اور نیز
وقت کی محتاج اور پھر محدود ہے لیکن خدا کی پیدا کرنے کی قدرت نہ کسی مادہ کی محتاج ہے نہ کسی
1070
Page 1079
وقت کی محتاج اور غیر محدود ہے کیونکہ اس کی تمام صفات بے مثل و مانند ہیں اور جیسے کہ اس کی
کوئی مثل نہیں اس کی صفات کی بھی کوئی مثل نہیں.اگر ایک صفت میں وہ ناقص ہوتو پھر تمام
صفات میں ناقص ہوگا.اس لئے اس کی تو حید قائم نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ اپنی ذات کی طرح
اپنے تمام صفات میں بے مثل و مانند نہ ہو.پھر اس سے آگے آیت ممدوحہ بالا کے یہ معنے ہیں کہ
خدا نہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ کوئی اس کا بیٹا ہے کیونکہ وہ غنی بالذات ہے.اس کو نہ باپ کی حاجت
ہے اور نہ بیٹے کی.یہ توحید ہے جو قرآن شریف نے سکھلاتی ہے جو مدارا ایمان ہے.لیکچر لاہور، روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 154، 155 )
انصاری کا فتنہ سب سے بڑا ہے اس واسطے اللہ تعالیٰ نے ایک سورت قرآن شریف کی
تو ساری کی ساری صرف ان کے متعلق خاص کر دی ہے یعنی سورۃ اخلاص اور کوئی سورت ساری
کی ساری کسی قوم کے واسطے خاص نہیں ہے.أحد خدا کا اسم ہے اور احد کا مفہوم واحد سے بڑھ کر ہے.حمد کے معنی ہیں ازل سے
عنی بالذات جو بالکل محتاج نہ ہو.اقنوم ثلاثہ کے ماننے سے وہ محتاج پڑتا ہے.الحکم جلد 5 نمبر 12 مورخہ 31 مارچ 1901 ، صفحہ 9)
کہہ دو کہ وہ خدا ایک ہے.ھو خدا کا نام ہے.وہ ایک.وہ بے نیاز ہے.نہ کھانے
پینے کی اس کو ضرورت.نہ زمان یا مکان کی حاجت.نہ کسی کاباپ ، نہ بیٹا.اور نہ کوئی اس کا ہمسر
اور بے تغیر ہے.یہ چھوٹی سی سورت قرآن شریف کی ہے جو ایک سطر میں آجاتی ہے لیکن
دیکھو کس خوبی اور عمدگی کے ساتھ ہر قسم کے شرک سے اللہ تعالی کی تنزیہ کی گئی ہے.حصر عقلی میں شرک کے جس قدر قسم ہو سکتے ہیں ان سے اس کو پاک بیان کیا ہے.جو چیز آسمان
اور زمین کے اندر ہے وہ ایک تغیر کے نیچے ہے مگر خدا تعالیٰ نہیں ہے.اب یہ کیسی صاف اور
ثابت شدہ صداقت ہے.دماغ اسی کی طرف متوجہ ہوتا ہے.نور قلب جس کی شریعت دل میں ہے
اس پر شہادت دیتا ہے.قانونِ قدرت اسی کا موید و مصدق ہے یہاں تک کہ ایک ایک پتہ اس پر
1071
Page 1080
گواہی دیتا ہے.پس اس کو شناخت کرنا ہی عظیم الشان بات ہے.الحکم جلد 6 نمبر 19 مورخہ 24 رمئی 1902، صفحہ 5)
الضالین کے مقابل آخر کی تین سورتیں ہیں.اصل تو قُلْ هُوَ الله ہے اور باقی دونوں
سورتیں اس کی شرح ہیں.قُلْ هُوَ الله کا ترجمہ یہ ہے کہ نصاری سے کہہ دو کہ اللہ ایک ہے.اللہ
بے نیاز ہے.نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ کوئی اس کے برابر ہے.الحکم جلد 6 نمبر 8 مورخہ 28 /فروری 1902 صفحہ 5)
حضرت خلیفہ المسیح الاول رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:
ا هو هو بھی اللہ تعالیٰ کا نام ہے.توریت میں زیادہ تر یہی نام خدا تعالیٰ کا آتا ہے.عبرانی میں اس کا ترجمہ یہوواہ سے کیا جاتا ہے.اصل بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ چونکہ عبرانی
زبان عربی زبان سے بگڑ کر بنی ہے.اس واسطے یہ لفظ دراصل يَاهُوَ تھا.هُوَ اللہ تعالیٰ کا نام
ہے اور کیا حرف منادی ہے.جیسا کہ دعا میں کہا جاتا ہے اے خدا ، یا اللہ.اسی سے بدل
کر انگریزی میں جہوا ( Jehoah) بن گیا ہے.الغرض هُوَ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے
ایک اسم ہے.الله : یہ نام خدا کے واسطے عربی زبان میں اسم ذات ہے.خدا تعالیٰ کا خاص نام ہے جو
صرف اسی کی ذات پر بولا جاتا ہے.دوسری کسی زبان میں خدا تعالیٰ کے واسطے کوئی ایسا نام
نہیں جو صرف اللہ تعالیٰ کے واسطے بولا جاتا ہو اور ایک مفر دلفظ ہو اور کسی دوسرے کے واسطے
کبھی استعمال نہ ہوتا ہو.مثلاً انگریزی زبان میں اللہ تعالیٰ کے واسطے دو لفظ بولے جاتے ہیں.ایک گاڈ (God) اور دوسر الارڈ (Lord).سو ظاہر ہے کہ گاڈ (God) کا لفظ انگریزی زبان
میں تمام رومی اور یونانی اور ہندی بتوں پر بولا جاتا ہے اور دیوتاؤں کے واسطے بھی استعمال
ہوتا ہے.اور لارڈ کا لفظ تو ایسا عام ہے کہ ایک معمولی فوج کا افسر بھی لارڈ ہوتا ہے.اور ایک
صوبہ کا حاکم بھی لارڈ ہوتا ہے.بلکہ ولایت میں پارلیمنٹ کے اعلی حصے کے تمام ممبر لارڈ ہی
1072
Page 1081
ہوتے ہیں.ایسا ہی فارسی زبان میں اللہ تعالیٰ کے واسطے کوئی خاص لفظ نہیں.جو لفظ زیادہ تر اللہ تعالیٰ
کے واسطے بولا جاتا ہے وہ خدا یا خداوند ہے.خدا ایک مرکب لفظ ہے.اور اس کے معنے ہیں
خود آ.جو خود بخود ہے.اور کسی نے اس کو جنا نہیں.اور فارسی لٹریچر میں یہ الفاظ اوروں کے
واسطے بھی استعمال میں آتے ہیں.ایسا ہی سنسکرت زبان میں جس قدر اللہ تعالیٰ کے نام ہیں وہ
سب صفاتی ہیں.کوئی اسم ذات نہیں.رض
لا حمد : اس سردار کو کہتے ہیں جس کی طرف وقت حاجت قصد کیا جاوے.چونکہ اللہ
تعالی تمام انسانوں کو سب حاجتوں کے پورا کرنے کے لئے قدرتِ تام رکھتا ہے اس واسطے
اس کی صفت میں یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے.اسی لحاظ سے سید سردار کو بھی کہتے ہیں.کیونکہ تمام
قوم اپنے سردار کی محتاج ہوتی ہے.حضرت ابن عباس کی حدیث سے بھی ان معنوں کی
تصدیق ہوتی ہے.جس میں لکھا ہے کہ جب یہ سورۃ شریف نازل ہوئی تو اصحاب نے سوال
کیا کہ یارسول اللہ صل علی محمد کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا.هُوَ السَّيْدُ الصَّمَدُ الَّذِي
يُصْمَدُ إِلَيْهِ في الحوائج وہ سردار ہے جس کی طرف لوگ احتیاج کے وقت قصد کرتے
ہیں.پھر لغت میں عربی میں حمد اس کو کہتے ہیں جس کا جوف نہ ہو یعنی اس کے اندر کوئی چیز نہ
جاسکے.نہ اس میں سے کوئی چیز نکلے.ایسا ہی حمد اس شفاف پتھر کو بھی کہتے ہیں جس پر
گرد و غبار نہ پڑ سکے.مفسرین نے مختلف پہلوؤں کے لحاظ سے لفظ حمد کی تفسیر کئی طرح سے
کی ہے جس میں سے بعض کو اس جگہ نقل کیا جاتا ہے.1 - حمد وہ عالم ہے جس کو تمام اشیاء کا علم ہو اور وہ بجز ذات الہی کے دوسرا نہیں.2 - حمد حلیم کو کہتے ہیں کیونکہ سید و ہی ہو سکتا ہے جو حلم اور کرم کی صفات اپنے اندر
رکھتا ہے.3 - حمد وہ سردار ہے جس کی سرداری اور سیادت انتہائی اعلیٰ درجہ تک ہو.(ابن مسعود وضحاک)
1073
Page 1082
4.صمد خالق الاشیاء ہے(آصم)
5.حمد وہ ذات ہے جو چاہے سو کرے اور حکم کرتا ہے جو چاہتا ہے.اس کے حکم کو کوئی
پیچھے نہیں کر سکتا اور اس کی قضا کو کوئی ٹال نہیں سکتا.( حسین بن فضل )
6 - حمد وہ شخص ہے جس کی طرف لوگ حاجت کے وقت رغبت کرتے ہیں اور مصیبت
کے وقت اس کے پاس اپنی فریاد لے جاتے ہیں.(سدی)
7.سید المعظم کو حمد کہتے ہیں.8_حمد غنی کو کہتے ہیں..حمد وہ ہے جس کے اوپر اور کوئی نہ ہو.جیسا کہ قرآن شریف میں مذکور ہے.وَهُوَ
الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ (الانعام (19)
10.حمد وہ ہے جو نہ کھاتا ہے اور نہ پیتا ہے پر دوسروں کو کھلاتا ہے اور پلاتا ہے.( قتادہ )
11.حسن بصری کا قول ہے کہ حمد وہ ہے جو لم یزل ہے اور لایزال ہے.اور اس کے
لئے زوال نہیں.12 - حمد وہ ہے جس پر موت نہیں اور نہ اس کا کوئی وارث ہوگا اور آسمان و زمین کی
میراث اسی کی ہے ( ابن ابی کعب )
13.حمد وہ ہے جس پر نیند کا غلبہ نہیں اور نہ اس سے سہو صادر ہوتا ہے ( یمان وابو مالک)
14 - حمدوہ ہے کہ جن صفات سے وہ متصف ہوتا ہے دوسرا کوئی نہیں ہوسکتا (ابن کیسان )
15.حمد وہ ہے جس میں کوئی عیب نہ ہو ( مقابل این خبان )
16.حمد وہ ہے جس پر کوئی آفت نہیں پڑ سکتی ( ربیع بن انس )
17.حمد وہ ہے جو تمام صفات میں اور تمام افعال میں کامل ہو ( سعید بن جبیر )
18.حمد وہ ہے جو غالب ہو اور مغلوب نہ ہو ( جعفر صادق )
19.حمد وہ ہے جو سب سے مستغنی ہو ( ابوھریرہ)
1074
Page 1083
20.حمد وہ ہے کہ خلقت اس کی کیفیت پر مطلع ہونے سے نا امید ہو.21 - حمد وہ ہے جو نہ جنتا ہے اور نہ اس کو کسی نے جنا.کیونکہ جو جنتا ہے لامحالہ اس
کاوارث ہوتا ہے.اور جو خود جنا گیا ہے وہ ضرور مرتا ہے.گویا صمد کے بعد کلمہ لخم يلد
وَلَمْ يُولَدُ.اس کا بیان معنی اور تشریح ہے.( ابو العالیہ )
وہ
22.حضرت ابن عباس فرماتے ہیں.إِنَّهُ الكَبِيرُ الَّذِي لَيْسَ فَوْقَهُ أَحَدٌ صَمَدُ وَهِ
کبیر ہے جس کے اوپر اور کوئی نہیں.لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدُ.وہ جنتا ہے اور نہ جنا گیا ہے.نہ اس کا کوئی ولد ہے اور نہ وہ کسی کا ولد
ہے.اس آیہ شریفہ میں ان تمام مذاہب باطلہ کا بالخصوص رڈ ہے جن میں اللہ تعالی کے بیٹے اور اولاد
فلاں
مانی جاتی ہے.جیسا کہ اس زمانہ کے عیسائی یسوع مسیح کو ولد اللہ اور یعنی اللہ کہتے ہیں.اس پر ایک سوال ہوا ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے لم یلد پہلے کیوں رکھا ہے
اور لخ یو لن پیچھے کیوں رکھا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر مشرکین کا یہ مذہب ہوتا ہے کہ
شخص خدا کا بیٹا تھا یا فلاں عورت خدا کی بیٹی تھی.مگر یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص خدا
کا باپ تھا یا فلاں عورت خدا کی ماں تھی.گو عیسائیوں کے جاہل فرقہ نے اس شرک میں کمال
را کیا ہے کیونکہ ان کے درمیان مریم کو خدا کی ماں کہا جاتا ہے اور ایک بڑا فرقہ عیسائیوں
کا اب تک مریم کی پرستش کرتا ہے.وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ : اور نہ اس کے واسطے کوئی کفو ہے.کُفو کے لغوی معنے
ہیں.نظیر اور مثیل.عرب میں بولا کرتے ہیں هَذَا كُفُوكَ أَى نَظِيرُكَ یہ تیرا کفو ہے.حضرت ابن عباس فرماتے ہیں لَيْسَ لَهُ كُفُو وَلَا مِثْلُ.رض
مجاہد کا قول ہے کہ کفو سے مراد صاحبہ یعنی جوڑو ہے.جیسا کہ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے
قرآن شریف میں فرمایا ہے بَدِيعُ السَّمَوتِ وَالْأَرْضِ أَلَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ
صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلّ شَیءٍ ( الانعام 102 ) وہ آسمانوں کا اور زمین کا بنانے والا ہے.اس کا ولد
1075
Page 1084
کہاں سے آ گیا جب کہ اس کی کوئی جوڑو نہیں.اور اس نے ہر شے پیدا کی ہے اور ہر شے اس
کی مخلوق ہے.نہ کہ اولاد.یہ سورۃ آخری زمانہ کے عظیم الشان فتنہ عیسائیت سے بچنے کے واسطے ایک بڑا ہتھیار
ہے.اس سورۃ میں اللہ تعالیٰ کی توحید پر بالخصوص زوردیا گیا ہے کہ وہ ایک خدا ہے.اس کا
کوئی بیٹا نہیں.اور نہ اس کا کنبہ قبیلہ ہے.اس میں عیسوی مذہب کی تردید کی گئی ہے
کیونکہ دین عیسوی کا تمام دارو مدار تثلیث پر ہے کہ ایک خدا باپ ہے اور ایک خدا بیٹا اور
ایک خداروح القدس ہے.عیسائیوں نے ایک کنبہ خدا کا یہاں مقرر کیا ہے.کوئی باپ
ہے.کوئی بیٹا ہے.کوئی روح القدس ہے.مگر اللہ تعالیٰ نے ان سب کی تردید کی ہے کہ خداوہ
ہے جو لم یلد ہے.کسی کا باپ نہیں اور آخر یولد ہے.کسی کا بیٹا نہیں.اور لَمْ يَكُن لَّهُ
كُفُوًا أَحَدٌ ہے.نہ اس کے برابر کوئی روح القدس وغیرہ ہے.ا لَمْ يَلِد وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ - ان ہر سہ کلمات کے ساتھ متثلیث کورڈ
کر دیا گیا ہے.اور اس رڈ کی دلیل الفاظ احد اور حمد میں بیان کی گئی ہے.کیونکہ جو ایک
ہے وہ تین کس طرح ہو سکتا ہے.اور جو یگانہ ہے اس کے ساتھ دوسرا تیسرا اس کی مانند کیونکر
بن سکتا ہے.اور وہ حمد ہے.کسی کا محتاج نہیں.یسوع تو کھانے پینے کا محتاج تھا....وہ
جو محتاج ہے وہ حمد نہیں ہوسکتا.اور جو صمد نہیں وہ خدا نہیں.حمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کا ملہ سے اس سورۃ شریف کو قرآن شریف کے آخر میں رکھ
کر اس امر کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ آخری زمانہ کا فتنہ یہ ہوگا کہ تین خدا مانے جاویں گے.ایک خدا کا باپ بنایا جاوے گا.ایک خدا کا بیٹا بنایا جاوے گا.ایک تیسرا بھی ہو گا جو ان کی مانند
اور مثل ہوگا.ایک روایت میں ہے عیسائیوں ہی نے سوال کیا تھا کہ آپ کے خدا کی کیا
صفات ہیں؟ اور ان کے سوال کے جواب میں یہ سورۃ نازل ہوئی تھی.اس فتنہ کو مٹانے والا وہ
شخص ہو گا جو خدا کو احد اور حمد مانتا ہوگا.اور اس امر کو دنیا کے آگے ثابت کر دے گا کہ خدا
حمد ہے.اپنے بندوں کی حاجات کو پوری کرتا ہے.بندے اپنی ضرورتوں کے وقت اسی کی
1076
Page 1085
طرف رجوع کرتے ہیں اور وہ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے.چنانچہ حضرت مسیح موعود کے
اور خوارق میں سے آپ کی دعاؤں کی قبولیت ہے جس میں مقابلہ کے واسطے تمام جہان کے عیسائیوں،
آر یوں وغیرہ کو بارہا چیلنج دیا جا چکا ہے مگر کسی کی طاقت نہیں کہ اس مقابلہ میں کھڑا ہو سکے.(ماخوذ از حقائق الفرقان زیر تفسیر سورۃ الاخلاص )
حضرت خلیفہ المسیح الثانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:
سورۃ اخلاص مگی بھی ہے اور مدنی بھی.اس سورۃ کا نزول دومرتبہ ہوا.ایک دفعہ مکہ میں
اور ایک دفعہ مدینہ میں.اس سورۃ کے متعدد نام مختلف تفاسیر میں مروی ہیں.اور یہ ناموں کی کثرت اس کے
کثرت مضمون کی طرف اشارہ کرتی ہے.چنانچہ وہ نام یہ ہیں:.1 ـ سورة التفرید.کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے اور فرد ہونے اور تثلیث وغیرہ کی
تردید اس سورۃ میں کی گئی ہے.2.سورۃ التجرید.کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لاثانی ہونے کا اس میں بیان ہے.3.سورۃ التوحید - کیونکہ توحید کا ایسا واضح بیان کسی دوسری کتاب میں نہیں ہے.4.سورۃ الاخلاص.کیونکہ یہ انسان کے اندر اخلاص پیدا کرتی ہے اور خدا تعالیٰ کے
ساتھ اس کا تعلق جوڑتی ہے.5.سورۃ النجاۃ.کیونکہ اس بات پر پورا یقین رکھنے سے کہ خدا ایک ہے انسان نجات
پاتا ہے.6.سورۃ الولایۃ.کیونکہ یہ سورۃ پورے علم اور عمل اور معرفت کا ذریعہ ہو کر انسان کو درجہ
ولایت تک پہنچا دیتی ہے.7- سورة المعرفة - کیونکہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اسی کلام کے ذریعہ حاصل ہوتی ہے.چنانچہ جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نماز پڑھتے ہوئے سورۃ الاخلاص
1077
Page 1086
کی تلاوت کی تو رسول کریم علااللہ نے اس سورۃ کو سن کر فرمایا کہ اس شخص نے اپنے رب کی
معرفت حاصل کرلی.8 - سورة الجمال - حدیث شریف میں آیا ہے کہ اِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَال کہ اللہ تعالیٰ
جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے.رسول کریم علیم سے سوال کیا گیا کہ اللہ کا جمال کیا ہے؟
آپ نے فرمایا اس کا آحد صَمَد لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدُ ہونا.9- سورة المُقشقشة مُقشقشہ کے معنے ہیں بری کرنے والی.جب کوئی بیمار شفا
پاتا ہے تو اہل عرب کہتے ہیں تَفَشَّقَشَ الْمَرِيضُ عما ہے.یعنی بیمار نے اپنی اس بیماری سے شفا
پائی جس میں مبتلا تھا.چونکہ یہ سورۃ شرک اور نفاق سے انسان کو بری کر کے خدا تعالیٰ کا خالص
بندہ بنادیتی ہے اس واسطے اس سورۃ کا نام مقشقشة رکھا گیا ہے.10.سورۃ المعوذہ.کیونکہ احادیث میں آتا ہے کہ رسول کریم ملایم حضرت عثمان بن -
مظعون کے پاس تشریف لے گئے اور قُل هُوَ الله احد اور سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ کر اُن پر
پھونکا.اور ان کو یہ ہدایت کی کہ ان سورتوں کے ذریعہ اللہ تعالی کی پناہ حاصل کیا کریں.11 - سورة الصمد - کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی صفت صمد کا ذکر آتا ہے جس میں اس بات
کو بیان کیا گیا ہے کہ کائنات کا ہر ذرہ اس کا محتاج ہے.12 - سورة الاساس رسول کریم عالم نے فرمایا ہے کہ أُيْسَتِ السَّموتُ السَّبْعُ
وَالْأَرْضُونَ السَّبْعُ عَلَى قُلْ هُوَ اللهُ اَحَدٌ یعنی ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں کا قیام
قُلْ هُوَ الله احد کی وجہ سے ہے.اس کا مطلب یہ ہے کہ تثلیث کا عقیدہ آسمانوں اوز مین کی
بربادی کا موجب ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تَكَادُ السَّمَوتُ يَتَفَطَرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُ
الْأَرْضُ وَتَخِرُ الْجِبَالُ.قریب ہے کہ آسمان اس گندے عقیدہ کی وجہ سے پھٹ جائیں اور
زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے اور پہاڑ گر کر ریزہ ریزہ ہوجائیں اور یہ مطلب بھی ہوسکتا ہے کہ
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَوْ كَانَ فِيْهِمَا الهَهُ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَنَا (الانبیاء (23) که اگر زمین و آسمان
میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور معبود ہوتا تو زمین و آسمان کا نظام درہم برہم ہو جا تا گویا توحید کا
1078
Page 1087
عقیدہ اس دنیا کی آبادی کی بنیاد ہے.13 ـ سورۃ المانعه - کیونکہ یہ عذاب قبر سے بچاتی ہے.حضرت ابن عباس روایت
کرتے ہیں کہ جب رسول کریم صلیم کو معراج ہوا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا أعطيتك
سُوْرَةُ الْإِخْلَاصِ وَهِيَ مِنْ ذَخَائِرِ كُنُوزِ عَرْشِي وَهِيَ الْمَانِعَةُ تَمْنَعُ عَذَابَ الْقَبْرِ وَنَفَحَاتِ
النيرانِ.کہ میں نے تمہیں سورۃ الاخلاص دی ہے اور یہ میرے عرش کے خزانوں کے ذخائر
میں سے ایک ہے اور یہ عذاب قبر اور آگ کے شعلوں سے بچانے والی ہے کیونکہ جو سچی توحید
پر قائم ہو جائے اس کو آگ چھو نہیں سکتی.14 - سورة المحضر.کیونکہ جب یہ پڑھی جائے تو فرشتے اس کو سننے کے لئے حاضر
ہوتے ہیں.15- سورة البراءة.یعنی آگ سے یا شرک سے محفوظ رکھنے والی.چنانچہ حدیث میں آتا
ہے کہ رسول کریم ملایم نے ایک شخص کو یہ سورۃ پڑھتے سُنا.تو آپ نے فرمایا آما هذَا فَقَد
برء من الشرك.کہ یہ شخص تو شرک سے پاک ہو گیا.پھر آپ نے فرمایا جس شخص نے
سومرتبہ اس سورۃ کونماز میں یا اس کے علاوہ پڑھا تو وہ آگ سے محفوظ ہو گیا.16.سورۃ المذگرہ.کیونکہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو یاد دلاتی ہے.17 سورة النور - کیونکہ رسول کریم علام فرماتے ہیں.اِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ نُورًا وَنُوْرُ
الْقُرآنِ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ.کہ ہر چیز کا ایک نور ہوتا ہے اور قرآن کا نور قُلْ هُوَاللهُ أَحَدٌ ہے.18 - سورۃ الامان - کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ توحید کو ماننے
والا قلعہ میں داخل ہو جاتا ہے اور اس سورۃ میں توحید کا ذکر ہے.پس یہ عذاب سے امن
میں رکھنے والی ہے.19 - سورة المنفّرة یعنی شیطان کو بھگانے والی.( تفسیر رازی)
رسول کریم علی العلیم نے اس سورۃ کو ٹکٹ قرآن قرار دیا ہے.چنانچہ آپ فرماتے
1079
Page 1088
ہیں.مَنْ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ فَكَانَمَا قَرَأَ ثُلُثَ القُرانِ.(فتح القدير ) یعنی جس نے
سورۃ الاخلاص کو پڑھا گویا اس نے قرآن کریم کے تیسرے حصہ کو پڑھا.نیز ابوسعید خدری کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا.وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهَا
لَتَعْدِلُ ثُلتَ الْقُرآنِ.(فتح القدیر) یعنی وہ ذات جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں اس
کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ سورۃ الاخلاص قرآن کریم کے تیسرے حصہ کے برابر ہے.حمۃ اس سورۃ کے مخلث قرآن ہونے سے یہ مراد نہیں کہ یہ سورۃ قرآن کریم کے حجم کا تیسرا
حصہ ہے.بلکہ صرف یہ مراد ہے کہ اس کا مضمون خاص اہمیت رکھتا ہے.در حقیقت قرآن کریم کا کام توحید کو ثابت کرنا اور غلط عقائد کو مٹانا ہے.پس جب اس
سورۃ نے نہایت جامع مانع الفاظ کے ساتھ مختصر طور پر وہ مضمون ادا کر دیا جس سے غلط عقائد کا
ابطال ہوتا ہے اور توحید کی حقیقت کو بیان کر دیا تو یہ سورہ مثلث قرآن کیا بلکہ سارے قرآن کے
برابر ہو گئی.پس رسول کریم علی ایم کا اس سورۃ کو ملث قرار دینا مبالغہ نہیں بلکہ اس کے
مضمون کی اہمیت کے پیش نظر ہے.چنانچہ اسی اہمیت کے پیش نظر رسول کریم صلی نے اس
کو اعظمُ السُّورِ کے نام سے بھی یاد کیا ہے.(روح المعانی)
حمد روایات میں آتا ہے کہ جب یہ سورۃ نازل ہوئی تو اس کے ساتھ ستر ہزار فرشتے نازل
ہوئے.( روح البیان)
یہ روایت بھی اس سورۃ کی اہمیت پر دلالت کرتی ہے.اس قسم کی روایات کے متعلق جن
میں سورتوں کے ساتھ فرشتوں کے نزول کا ذکر ہوتا ہے، یاد رکھنا چاہئے کہ اس سے نزول کے
وقت حفاظت مراد نہیں ہوتی بلکہ نزول کے بعد کی حفاظت مراد ہوتی ہے.اور وہ اس طرح کہ
ہر سورۃ کسی خاص مضمون کے بارہ میں ہوتی ہے اور بعض دفعہ اس میں پیشگوئیاں ہوتی ہیں جن
کے پورا ہونے پر اس سورۃ کی سچائی کا انحصار ہوتا ہے.یہ پیشگوئیاں بعض دفعہ طبعی تغیرات
کے متعلق ہوتی ہیں اور بعض دفعہ انسانی اعمال کے متعلق.انسانی اعمال کے متعلق جو پیشگوئیاں
1080
Page 1089
ہوتی ہیں وہ اس لحاظ سے خاص اہمیت رکھتی ہیں کہ جن کے عذاب کی ان پیشگوئیوں میں خبر ہو
وہ اس عذاب کو ٹالنے کی پوری کوشش کرتے ہیں.اور چونکہ بالعموم غیر معمولی طور پر مخالف
حالات میں کی جاتی ہیں.اس لئے دنیوی سامانوں کے لحاظ سے اُن کا پورا ہونا بظاہر ناممکن یا
غیر اغلب نظر آتا ہے.اور اسی وقت اُن کے پورا ہونے کی کوئی صورت پیدا ہو سکتی ہے جبکہ
اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی امداد کا انتظام کیا جائے.پس جس سورۃ میں اس قسم کی پیشگوئیاں ہوں جن کے باطل کرنے کے متعلق زبردست
قوموں نے زور لگانا ہو اُن کے بارہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اُن ملائکہ کو جو دنیا کے مختلف
کاموں پر بطور مڈ بر مقرر ہیں ، ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ ایسے سامان پیدا کریں کہ وہ پیشگوئیاں
بغیر روک کے پوری ہوجائیں.گوسورۃ الاخلاص میں کوئی پیشگوئی نہیں.لیکن چونکہ اس میں توحید باری کا مضمون ہے اور
توحید کے خلاف آخری زمانہ میں دو خطرناک فتنے اٹھنے والے تھے اور وہ ایسے فتنے تھے کہ اگر
آسمانی فرشتوں کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ ان فتنوں کے مٹانے کا انتظام نہ فرماتا تو اسلامی
طاقتیں اُن کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھیں اور ان فتنوں کا مقابلہ مشکل تھا.پس اللہ تعالیٰ نے توحید کی
حفاظت کے لئے ستر ہزار فرشتوں کو لگا دیا تا کہ جہاں دجالی فتنہ اور یا جوج و ماجوج کا فتنہ
توحید کے خلاف نبردآزما ہو اور پورے سازوسامان کے ساتھ اس پر حملہ آور ہو.وہاں اُن کے
مٹانے کے لئے فرشتے آسمان سے اتریں اور مخالف حالات میں توحید کو دنیا پر قائم کر دیں.اور شرک اور دہریت کا قلع قمع ہو جائے اور جس طرح سے خدا تعالیٰ کی بادشاہت آسمان پر ہے
زمین پر بھی قائم ہو جائے.م اس سورۃ کے فضائل کے متعلق جو روایات بیان ہوئی ہیں اُن میں سے ایک روایت
حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ ایک انصاری مسجد قبا میں نماز پڑھایا کرتے تھے.جب بھی
وہ کوئی سورۃ نماز میں پڑھتے تو اس سے پہلے سورۃ الاخلاص پڑھ لیتے اور اس کے پڑھنے کے
بعد پھر کوئی اور سورۃ پڑھتے.مقتدیوں نے کہا کہ جب ایک رکعت میں ایک سورۃ پڑھنی کافی
1081
Page 1090
ہے تو دوسری سورۃ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے.اس پر انصاری نے کہا کہ میں تو سورۃ الاخلاص
کو پڑھنا نہیں چھوڑ سکتا خواہ مجھے امامت سے فارغ کر دو.اور چونکہ اس محلہ میں افضل ترین
شخص نماز پڑھانے کے لئے وہی تھے اس لئے اُن کو امامت سے الگ نہ کیا گیا.ہاں
رسول کریم علی جب اس محلہ میں تشریف لے گئے تو آپ کی خدمت میں معاملہ پیش کر دیا
گیا.تب رسول کریم علیم نے اس انصاری شخص سے اس سورۃ کو ہر رکعت میں پڑھنے کی
وجہ دریافت کی تو اس صحابی نے جواب دیا اني احبها یعنی میں اس سورۃ کے مطالب سے محبت
رکھتا ہوں.کیونکہ یہ خدا تعالیٰ کی توحید کو لئے ہوئے ہے.اس پر رسول کریم علیم نے فرمایا
حُبُّكَ إِيَّاهَا أَدْخَلَكَ الْجَنَّةَ.(فتح البیان) کہ تمہارے اس سورت سے محبت کرنے نے تم
کو جنت میں داخل کر دیا.پس رسول کریم علی ایم کے اس ارشاد سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان
اگر خالص توحید پر قائم ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل تو گل رکھے تو وہ جنت میں داخل ہو
جاتا ہے.اسی طرح روایات میں آیا ہے...ایک شخص رسول کریم عیلام کی خدمت میں حاضر ہوا
اور اپنی محتاجی کی شکایت کا ذکر کیا.آپ نے فرمایا کہ جب تو گھر میں داخل ہو اور گھر میں کوئی
موجود ہو تو اس کو السّلامُ عَلَيْكُمْ کہا کرو.اور اگرگھر میں کوئی موجود نہ ہو تو اپنے نفس پر سلام
بھیجو اور اس کے بعد قُلْ هُوَ الله احد ایک دفعہ پڑھو.روایات میں آتا ہے کہ اس شخص نے
آپ کے ارشاد پر عمل کرتے ہوئے ایسا ہی کیا.چنانچہ اس کے نتیجہ میں نہ صرف یہ کہ اس کی
غربت دُور ہو گئی.بلکہ اس کے پاس روپیہ اور مال کی اتنی کثرت ہوگئی کہ وہ اپنے پڑوسیوں اور
ہمسایوں کی بھی مدد کرتا تھا.حقیقت یہی ہے کہ جب انسان کو علم ہو کہ ایک خدا ہے جوسب طاقتوں کا مالک ہے.وہ
میرے کام میں برکت ڈال سکتا ہے.تو اس پر توکل کرے گا اور اُسی کے آگے جھکے گا.اور جب
محنت اور دعا کسی کے اندر جمع ہو جائیں تو اس کی مشکلات دور ہو جاتی ہیں.اور اس روایت میں
1082
Page 1091
محنت ، توکل اور دعا کا سبق سکھایا گیا ہے.ا حضرت عائشہؓ سے روایت کی گئی ہے کہ رسول کریم یا لیم جب رات کو بستر میں لیٹتے تو
آپ دونوں ہتھیلیاں جمع کرتے اور قُلْ هُوَ اللهُ أحد.قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ اور قُلْ اَعُوْذُ
بِرَبِّ النَّاس پڑھنے کے بعد ہتھیلیوں میں پھونکتے اور پھر سارے بدن پر مل لیتے.اور یہ فعل
آپ تین مرتبہ کرتے.رسول کریم علیل لیلی نے ان تینوں سورتوں کو اکٹھا پڑھنے اور ان کے ذریعہ دعا کرنے سے
اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ ان تینوں سورتوں کا جو قرآن مجید کے آخر میں رکھی گئی ہیں
گہرا اشتراک ہے.سورۃ الاخلاص میں توحید کامل کا ثبوت ہے اور دوسری دوسورتوں میں
دعاؤں کا ذکر ہے.قرآن کریم کی آخری تین سورتوں کا باہم جوڑ اور اشتراک ہے اور ان میں یہ بتایا گیا
ہے کہ پہلے تو حید کو سمجھنا چاہئے.اس کے بعد دعائے کامل پیدا ہوگی اور جب دعائے کامل
پیدا ہوگی تو پھر شر کا خاتمہ ہوگا.سورۃ الاخلاص ہے تو بہت مختصر لیکن اس میں کامل توحید کو پیش کیا گیا ہے.چنانچہ اس
میں تین امور کو پیش کیا ہے.1.خدا تعالیٰ کی ذات کو کہ وہ موجود ہے.2.خدا تعالی کے ذات میں منفر د ہونے کو یعنی یہ کہ وہ اکیلا ہے اور یہ کہ دو یا تین خدا نہیں.3.خدا تعالیٰ کے واحد فی الصفات ہونے کو.یعنی یہ کہ اس کی صفات میں کوئی ہمسری
نہیں کرسکتا.خدا تعالیٰ کے متعلق جو یقینی بات ہے اس کا نقطہ مرکزی یہ ہے کہ اللہ احد.اللہ کی
ذات ایسی ہے کہ ہر رنگ میں اور ہر طرح اپنے وجود میں ایک ہی ہے.نہ وہ کسی کی ابتدائی
کڑی ہے اور نہ آخری سرا.نہ کسی کے مشابہ ہے اور نہ کوئی اس کے مشابہ.احد کا لفظ اپنے اندر عجیب خصوصیت رکھتا ہے اور وہ یہ ہے کہ اس میں کسی رنگ میں
1083
Page 1092
ڈوئی کا خیال نہیں پایا جا تا...احد کا لفظ یہ مضمون بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں یکتا ہے.یہ دو قسم کی نفی
کرتا ہے.پہلی یہ کہ وہ دو سے ایک نہیں ہوا.اور دوسری یہ کہ وہ ایک سے بھی دو نہیں ہوا.اس مختصر سی سورۃ کے ذریعہ جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی ہستی کا ثبوت دیا ہے.وہاں شرک
کا بھی گلی استیصال کر دیا ہے.شرک دو قسم کا ہوتا ہے.ایک تو یہ کہ کئی وجود خدا کی حیثیت رکھنے والے ہوں.چاہے اس
سے چھوٹے ہوں یا بڑے.دوسرے یہ کہ خدا کے سوا باقی ہو تو مخلوق ہی مگر اُسے خدائی کا درجہ دیا
گیا ہو.تو ایک شرک فی الذات ہے اور دوسرا شرک فی الصفات.اللہ تعالیٰ نے قُلْ هُوَ اللهُ
احد کہ کر تمام اُن لوگوں کے عقائد کی تردید کر دی جو تین خدا کہتے ہیں یا دو خداؤں کے قائل
ہیں.یا خدا کا بیٹا یا بیٹیاں تجویز کرتے ہیں.یا اور بتوں کو پوجتے ہیں.چنانچہ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ
کے بعد الله الصَّمَدُ اور پھر لَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا اَحَدٌ کہہ کر بتادیا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں جو
لوگ شرک کرتے ہیں اور دوسروں کو اس کی صفات میں شریک قرار دیتے ہیں یہ اُن کی غلطی
ہے خواہ کتناہی کوئی بڑا انسان ہو وہ اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے.نہ اس کے رتبہ کو کوئی پہنچ سکتا ہے
اور نہ اس کا کوئی شریک فی الفعل ہو سکتا ہے.الله الصمد.صد ایسی ہستی کو کہتے ہیں کہ جو خود کسی کی محتاج نہ ہو بلکہ باقی سب چیزیں
اس کی محتاج ہوں.قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ میں یہ دعویٰ تھا کہ اللہ ہے اور ایک ہے.اب اس دعویٰ
کی دلیل اللہ الصمد میں دی گئی ہے.اس سورۃ کی ہر آیت پہلی آیت کے مضمون کی ایک مضبوط دلیل ہے.چنانچہ پہلے فرمایا
هُوَ اللهُ أَحَدٌ.یعنی حقیقت یہ ہے کہ اللہ منفرد ہے اور پھر فرمایا کہ اس کا ثبوت یہ ہے کہ
الله الصمد دنیا کی ہر چیز اس کی محتاج ہے.اور جب ساری چیزیں اس کی محتاج ہیں اور وہی
ہمارے سب کام پورے کرتا ہے تو پھر کسی اور رب کی ضرورت ہی کیا رہ جاتی ہے.الصمد کے دوسرے معنے الرفیع کے ہیں.یعنی بلند درجات والا.ان معنوں کے لحاظ
1084
Page 1093
الله الصمد کے معنے یہ ہوں گے کہ وہ ذات جس کے متعلق ہم نے کہا ہے کہ وہ احدیت
کی شان رکھتا ہے وہ رفیع الدرجات ہے اور غیر محدود ہے اور قیاسات سے بالا ہے.احمد کے ایک معنے الدائم کے بھی ہیں یعنی ابدی.گویا بتایا گیا ہے کہ اللہ ہے
اور ایک ہے اور یہ کہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا.نہ اس سے کوئی پہلے وجود تھا اور نہ بعد
میں ہوگا بلکہ وہی ہے جو اول بھی ہے اور آخر بھی.الله الصَّمَدُ کے بعد لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولّد کہہ کر اللہ تعالیٰ کی صمدیت کی دلیل دی اور بتایا
کہ احتیاج دو باتوں کے سبب سے پیدا ہوتی ہے.اول ابتدائی تعلقات کی وجہ سے.دوم آئندہ کے تعلقات کی وجہ سے.ابتدائی تعلقات سے مراد یہ ہے کہ کسی چیز کے نیست سے ہست میں آنے اور عالم وجود میں
ظاہر کئے جانے کا کوئی سبب ہو اور جس کے پیدا ہونے اور نیست سے ہست میں آنے کا کوئی
سبب ہوگا لازماً وہ وجود محتاج ہوگا.کیونکہ اگر وہ سبب نہ ہوتا تو اُس کا وجود ظاہر نہ ہوسکتا.اور
آئندہ کے تعلقات سے مراد یہ ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو.کیونکہ اولاد کا ہونا نہ صرف عورت کی
احتیاج کو ثابت کرتا ہے بلکہ اولاد کا وجود خود اپنے نفس کے فانی ہونے کا بھی ثبوت ہوتا ہے.غرض لم يلد ولم يُولّد کہہ کر اللہ تعالیٰ نے دونوں قسم کے تعلقات کی نفی کر دی اور
ایک طرف تو اس کی صمدیت کا ثبوت دیا اور دوسری طرف اس کی احدیت کا ثبوت دے دیا.گویا یہ دو آیتیں مل کر پہلی دو آیتوں کا ثبوت ہیں.پھر لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولّد کہہ کر قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ کی صفت صمدیت کے متعلق ایک
شبہ کا بھی ازالہ کر دیا.وہ شبہ یہ پیدا ہوتا تھا کہ بے شک مان لیا کہ خدا تعالیٰ کی مدد کے بغیر کوئی
کام سر انجام نہیں دیا جا سکتا.مگر کیا یہ ممکن نہیں کہ اس کی طاقت کبھی ختم ہو جائے.کیا ایسا کوئی
امکان اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق تو نہیں؟ اس سوال کا جواب اللہ تعالیٰ نے تعمیلہ میں دیا اور
بتایا کہ اگر آئندہ اس کی طاقتیں ختم ہونے والی ہوتیں تو اس کا قائم مقام کوئی وجود پیدا ہوتا.مگر اُس
نے کوئی بیٹا نہیں جنا.اور بیٹوں سے وہی چیزیں مستغنی ہوتی ہیں جو اپنی ضرورت کے آخر تک
1085
Page 1094
قائم رہتی ہیں.پس لغم یلڈ نے ثابت کر دیا کہ اس کی طاقت کبھی ختم نہیں ہوگی اور اس کی
صمدیت ہمیشہ قائم رہے گی.حمد اس آیت میں ایک اور بات جو قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ اس جگہ آخر ییں کے الفاظ
پہلے رکھے گئے ہیں.اور لغم یولن کے بعد میں.حالانکہ آخر یلد ابدیت پر دلالت کرتا ہے اور
لم يولد از لیت پر دلالت کرتا ہے اور ازلیت پہلے ہوتی ہے اور ابدیت پیچھے ہوتی ہے.اس کا جواب یہ ہے کہ ازلیت کا علم کسی انسان کو نہیں ہوسکتا.کیونکہ انسان دور حاضر کی
پیدائش ہے.وہ ازلیت کا علم ابدیت سے ہی حاصل کر سکتا ہے.چونکہ تمام گزشتہ تاریخ عالم
اس بات کا ایک ثبوت ہے کہ کبھی بھی دنیا خدا کی مدد سے محروم نہیں رہی.اور دوسرے یہ ثابت
ہے اس کا کوئی لڑکا نہیں.اس لئے معلوم ہوا کہ وہ ابدی ہے اور جب وہ ابدی ہے تو لازماً ازلی
بھی ہے.کیونکہ آئندہ کی فنا سے وہی محفوظ رہ سکتا ہے جو گزشتہ پیدائش سے بھی محفوظ ہو.وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ
کھو کے معنے مثیل اور برابر کا درجہ رکھنے والے کے ہوتے ہیں....صرف یہی نہیں
کہ خدا کسی کا بیٹا نہیں یا خدا کا آگے کوئی بیٹا نہیں بلکہ اس کا مماثل اور مشابہ بھی کوئی نہیں.اس آیت میں ایک لطیف پیرایہ میں اس حقیقت پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے کہ باوجود اس کے
کہ خدا تعالیٰ کی بعض صفات کے مشابہ صفات انسانوں میں بھی پائی جاتی ہیں.پھر بھی خدا تعالیٰ
کا کوئی ہمتا اور ہمسر نہیں.کیونکہ انسان کے اندر جو صفات پائی جاتی ہیں وہ ایسے طور پر نہیں پائی
جاتیں کہ وہ خدا تعالیٰ کا کفو ہو سکے.یہ سورۃ آخری زمانہ میں دہریت اور عیسائیت جیسے خطرناک فتنوں کے مٹانے اور
اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی احدیت کو ثابت کرنے کے لئے اور تمام قوموں کو ایک نقطہ
مرکزی پر جمع کرنے کے لئے نازل کی گئی ہے.رسول کریم علیم کی بعثت سے پہلے اللہ تعالیٰ
کے مختلف نام دنیا میں بولے جاتے رہے.کوئی اُسے گاڈ (God) کہتا.اور کوئی پرمیشور.کوئی یزدان کہتا اور کوئی الو ہیم.اور لوگ اپنی نادانی سے یہ سمجھتے تھے کہ فلاں ہندوؤں کا خدا
1086
Page 1095
ہے اور فلاں عیسائیوں کا.بلکہ خود ان قوموں کی کتابوں میں لکھا ہوتا تھا کہ تمہارا خدا جو پرمیشور
یا الو ہیم ہے تمہیں یوں کہتا ہے.گویا پہلے زمانوں میں اللہ تعالیٰ کا وجود بھی ایک قومی ہو کر رہ گیا
تھا.آخر اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی علیم کے ذریعہ بنی نوع انسان پر اپنا اسم ذات یعنی لفظ
اللہ ظاہر کیا.اور دنیا کو بتایا کہ گاڈ اور یزدان اور الو ہیم وغیرہ سب اللہ کے نام کی طرف
اشارے ہیں.ورنہ اصل میں ایک ہی خدا ہے جس کا نام اللہ ہے.اسی حقیقت کی طرف
اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں بھی اشارہ فرمایا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمَوتِ وَالْأَرْضَ
لَيَقُولُنَّ الله - (لقمان 26) یعنی اگر تو ان سے پوچھے کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے تو
وہ کہیں گے اللہ نے.اس کے یہ معنے نہیں کہ وہ اللہ کا نام لیں گے.بلکہ مراد یہ ہے کہ وہ جو بھی
نام لیں گے اُن کا اشارہ اللہ ہی کی طرف ہوگا.پس اصل چیز ایک ہی ہے یعنی خواہ ہندو
اور عیسائی اس کا کوئی نام رکھیں مراد در حقیقت یہی ہے کہ اللہ سب چیزوں کا خالق ہے.پس
اللہ قومی نہیں بلکہ رب العالمین ہے اور دنیا کی ساری قومیں کسی نہ کسی نام سے اس کو مانتی اور
تسلیم کرتی ہیں.ماخوذ از تفسیر کبیرزیر تفسير سورة الاخلاص)
حضرت خلیفة المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے ماہ رمضان المبارک 2016 ء
کے آخری روز مسجد فضل لندن میں قرآن مجید کی آخری تین سورتوں کا درس ارشاد فرمایا.حضور انور
ایدہ اللہ نے اس میں فرمایا:
سورۃ اخلاص میں کامل تو حید کو بیان کیا گیا ہے.یہ کہ خدا تعالیٰ کی ذات موجود ہے.یہ
کہ خدا تعالیٰ کی ذات منفرد ہے.وہ یکتا ہے.اور یہ کہ وہ اپنی صفات میں واحد ہے.اس کی
صفات کا کوئی مقابلہ نہیں کرسکتا.یہ جو خدا تعالیٰ کے نہ ماننے والے ہیں آجکل ان کی تعداد بڑی بڑھتی جارہی ہے.یہ کہتے
ہیں کہ خدا تعالیٰ کا کوئی وجود نہیں ہے اور اس چیز نے اکثریت کو مذہب سے دُور کر دیا ہے.1087
Page 1096
اس شک میں مبتلا ہیں اور دوسروں کو بھی اس شک میں ڈالتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کا کوئی وجود نہیں
ہے.قرآن اعلان کرتا ہے کہ خدا تعالیٰ ہے.تم اندھے ہو، تمہیں نظر نہیں آتا.تم دنیا میں
ڈوبے ہوئے ہو تمہیں کس طرح خدا تعالیٰ اپنے وجود کا ثبوت دے.ہر دنیاوی کام کے لئے
انسان کوشش کرتا ہے، جہاد کرتا ہے.اللہ تعالیٰ کے لئے یہ چاہتے ہیں کہ بغیر کوشش کے
مل جائے ، کچھ ترد نہ کرنا پڑے.اور وہی لوگ ہیں جو خدا تعالی کی طرف بڑھنے کی کوشش
نہیں کرتے اور یہی چیز ہے جو انہیں شرک میں مبتلا کر رہی ہے.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا (العنكبوت 70) یعنی اور وہ لوگ جو ہم سے ملنے
کی کوشش کرتے ہیں ہم ضرور انہیں اپنے راستے دکھاتے ہیں.حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس کی وضاحت میں فرماتے ہیں کہ :
جولوگ ہماری راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں اور ہماری طلب میں کوشش کو انتہا تک پہنچا
دیتے ہیں انہی کے لئے ہمارا یہ قانون قدرت ہے کہ ہم ان کو اپنی راہ دکھلا دیا کرتے ہیں.“
(حقیقۃ الوحی ، روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 117)
کوشش کو انتہا تک پہنچانا ضروری ہے.صرف کوشش نہیں.آدھے راستے میں چھوڑ
نہیں دینا.پھر آپ نے مزید وضاحت کے طور پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ :
جولوگ ہماری راہ میں جو صراط مستقیم ہے مجاہدہ کریں گے تو ہم ان کو اپنی راہیں بتلا دیں
گئے ( فرمایا کہ ) اور ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ کی راہیں وہی ہیں جو انبیاء کو دکھلائی گئیں تھیں.“
66
( شهادة القرآن، روحانی خزائن جلد 6 صفحه 352)
پس ذاتی تجربہ تو اللہ تعالیٰ کے وجود کا اُس وقت ہوگا جب اس کی طرف انسان قدم بڑھائے گا.یہ اللہ تعالیٰ نے شرط لگائی ہے.انسان کی کم علمی اور کسی چیز کو حاصل کرنے کی کوشش نہ کرنا یا
اس چیز کا اس کو حاصل نہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں بن جاتا کہ وہ چیز نہیں ہے یا اس کا وجود
نہیں ہے.پس یہی اصول خدا تعالیٰ کے وجود کی پہچان کے لئے بھی ضروری ہے.یہ تو ہے
1088
Page 1097
ذاتی طور پر اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کر کے اس کی پہچان کرنا اور اس کے وجود کا علم ہونا لیکن علمی
لحاظ سے بھی بے شمار باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا پتا دیتی ہیں.قرآن کریم میں پیشگوئیاں
ہیں، بیشمار پیشگوئیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کے کلام کی صداقت کا پتا دیتی ہیں.مثلاً
قرآن کریم میں سورۃ رحمن میں سمندروں کو ملانے کی پیشگوئی ہے کہ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِينِ
(الرحمن (20) که دوسمندروں کو ملا دے گا جو بڑھ بڑھ کے ملیں گے.مشرق میں بھی، مغرب
میں بھی اس کے نمونے موجود ہیں.سویز کنال ہے، پانامہ کنال ہے سمندروں کو ملانے والی.پھر قرآن کریم میں اور بھی بہت سی جگہ پیشگوئیاں ہیں.مثلاً سورۃ تکویر میں ہی پرانی
سواریوں کو ترک کرنے کی نئی اور آسان سواریوں کی ایجاد کی پیشگوئیاں ہیں جس سے فاصلے کم
ہوجائیں گے، دنیا ایک ہو جائے گی.چودہ سو سال پہلے ان باتوں کی خبریں کس نے آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کو دیں.اُسی خدا نے جو کہتا ہے کہ میں ہوں اور یکتا ہوں اور تمام صفات میں
کامل ہوں.جو عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَة خدا ہے.وہ علیم وخبیر ہے.تو یہ پیشگوئیاں پوری بھی
ہوگئیں اور ہو بھی رہی ہیں اور کوئی بھی نہیں جو کسی بھی لحاظ سے اللہ تعالیٰ کا ان باتوں میں شریک
ہو.پھر وہ سائنس کی باتیں ہیں جو آج دریافت ہو رہی ہیں.چودہ سو سال پہلے کے انسان کو پتا
نہیں لگ سکتیں.پس ہزاروں سال پرانی باتوں سے لے کر آج تک اور آئندہ کی خبریں دینے والا خدا ہے
جو ازل سے ہے اور ہمیشہ رہے گا.سب طاقتوں والا ہے.اس کا کوئی شریک نہیں.(ماخوذ از هفت روزه الفضل انٹر نیشنل 17 فروری 2017، صفحہ 4)
1089
Page 1099
XXXXXXXX
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ )
مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ
وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ
وَ مِنْ شَرِّ النَّقْتُتِ فِي الْعُقَدِة
وَ مِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَةً
سورة الفلق
1 - (میں) اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا
( اور ) بار بار رحم کرنے والا ہے (پڑھتا ہوں)
2.ہم ہر زمانہ کے مسلمان سے کہتے ہیں کہ ) تو
( دوسرے لوگوں سے ) کہتا چلا جا کہ میں مخلوقات
کے رب سے ( اس کی ) پناہ طلب کرتا ہوں.3 اس کی ہر مخلوق کی (ظاہری و باطنی ) برائی سے
بچنے کے لئے)
4.اور اندھیرا کرنے والے کی ہر شرارت سے
بچنے کے لئے ) جب وہ اندھیرا کر دیتا ہے.5.اور تمام ایسے نفوس کی شرارت سے ( بچنے کے
لئے بھی ) جو ( باہمی تعلقات کی ) گرہ میں (تعلق
تڑوانے کی نیت سے ) پھونکیں مارتے ہیں.6.اور ہر حاسد کی شرارت سے ( بھی ) جب وہ حسد پر محل
جاتا ہے.1091
Page 1100
حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں:
سورة الفلق اور سورۃ الناس یہ دونوں سورتیں سورۃ تبت اور سورۃ اخلاص کے لئے بطور
شرح کے ہیں اور ان دونوں سورتوں میں اس تاریک زمانہ سے خدا کی پناہ مانگی گئی ہے جب
کہ لوگ خدا کے مسیح کو دکھ دیں گے اور جب کہ عیسائیت کی ضلالت تمام دنیا میں پھیلے گی.“
(تحفہ گولڑوی، روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 218)
الضَّالین کے مقابل آخر کی تین سورتیں ہیں.اصل تو قُلْ هُوَ الله ہے اور باقی دونوں
سورتیں اس کی شرح ہیں.....سورۃ الفلق میں اس فتنہ سے بچنے کے لئے یہ دعا سکھائی قتل
اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ یعنی تمام مخلوق کے شر سے اس خدا کی پناہ مانگتا ہوں جو رب الفلق ہے یعنی
صبح کا مالک ہے یا روشنی ظاہر کرنا اسی کے قبضہ واقتدار میں ہے.رَبِّ الْفَلَقِ کا لفظ بتاتا ہے کہ اس وقت عیسائیت کے فتنہ اور مسیح موعود کی تکفیر اور تو بین
کے فتنہ کی اندھیری رات احاطہ کر لے گی اور پھر کھول کر کہا کہ شیر غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ اور میں
اس اندھیری رات کے شر سے جو عیسائیت کے فتنہ اور مسیح موعود کے انکار کے فتنہ کی شب تار
ہے، پناہ مانگتا ہوں.پھر لکھا وَ مِنْ شَرِ النَّفْتِ فِي الْعُقَدِ اور ان زنانہ سیرت لوگوں کی شرارت
سے پناہ مانگتا ہوں جو گنڈوں پر پھونکیں مارتے ہیں.گرہوں سے مراد وہ معضلات اور
مشکلات شریعت محمدیہ ہیں جن پر جاہل مخالف اعتراض کرتے ہیں اور ان کو ایک پیچیدہ صورت
میں پیش کر کے لوگوں کو دھو کہ میں ڈالتے ہیں اور یہ دو قسم کے لوگ ہیں.ایک تو پادری اور ان
کے دوسرے پس خوردہ کھانے والے اور دوسرے وہ ناواقف اور ضدی ملاں ہیں جو اپنی غلطی
کو تو چھوڑتے نہیں اور اپنی نفسانی پھونکوں سے اس صاف دین میں اور بھی مشکلات پیدا کر
دیتے ہیں اور زنانہ خصلت رکھتے ہیں کہ خدا کے مامور ومرسل کے سامنے آتے نہیں.پس ان
لوگوں کی شرارتوں سے پناہ مانگتے ہیں.اور ایسا ہی ان حاسدوں کے حسد سے پناہ مانگتے ہیں
1092
Page 1101
اور اس وقت سے پناہ مانگتے ہیں جب وہ حسد کرنے لگیں.“
الحکم جلد 6 نمبر 8 مورخہ 28 فروری 1902 ءصفحہ 5)
ا ”کہہ میں شریر مخلوقات کی شرارتوں سے خدا کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں اور اندھیری
رات سے خدا کی پناہ میں آتا ہوں.یعنی یہ زمانہ اپنے فساد عظیم کے رُو سے اندھیری رات کی
مانند ہے سوا ہی قوتیں اور طاقتیں اس زمانہ کی تنویر کے لئے درکار ہیں.انسانی طاقتوں سے یہ
کام انجام ہونا محال ہے.“
( براہین احمدیہ چہار حصص، روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 604 حاشیه در حاشیہ نمبر 3)
تم جو نصاری کا فتنہ دیکھو گے اور مسیح موعود کے دشمنوں کا نشانہ بنو گے یوں دعا مانگا کرو کہ
میں تمام مخلوق کے شر سے جو اندرونی اور بیرونی دشمن ہیں اس خدا کی پناہ مانگتا ہوں جو صبح کا
مالک ہے یعنی روشنی کا ظاہر کرنا اس کے اختیار میں ہے اور میں اس اندھیری رات کے
شرے جو عیسائیت کے فتنہ اور انکار مسیح موعود کے فتنہ کی رات ہے خدا کی پناہ مانگتا ہوں اُس
وقت کے لئے یہ دُعا ہے جبکہ تاریکی اپنے کمال
کو پہنچ جائے اور میں خدا کی پناہ اُن زن مزاج
لوگوں کی شرارت سے مانگتا ہوں جو گنڈوں پر پڑھ پڑھ کر پھونکتے ہیں.یعنی جو عقدے
شریعت محمدیہ میں قابل حل ہیں اور جو ایسے مشکلات اور معضلات ہیں جن پر جاہل مخالف
اعتراض کرتے ہیں اور ذریعہ تکذیب دین ٹھہراتے ہیں اُن پر اور بھی عناد کی وجہ سے پھونکیں
مارتے ہیں.یعنی شریر لوگ اسلامی دقیق مسائل کو جو ایک عقدہ کی شکل پر میں دھوکہ دہی کے
طور پر ایک پیچیدہ اعتراض کی صورت پر بنا دیتے ہیں تا لوگوں کو گمراہ کریں.اُن نظری اُمور پر
اپنی طرف سے کچھ حاشیے لگا دیتے ہیں.اور یہ لوگ دو قسم کے ہیں ایک تو صریح مخالف اور
دشمن دین ہیں جیسے پادری جو ایسی تراش خراش سے اعتراض بناتے رہتے ہیں.اور دوسرے
وہ علمائے اسلام ہیں جو اپنی غلطی کو چھوڑنا نہیں چاہتے اور نفسانی پھونکوں سے خدا کے فطری دین
میں عقدے پیدا کر دیتے ہیں اور زنانہ خصلت رکھتے ہیں کہ کسی مرد خدا کے سامنے میدان میں
نہیں آسکتے.صرف اپنے اعتراضات کو تحریف تبدیل کی پھونکوں سے عقدہ لا یخل کرنا چاہتے
ہیں اور اس طرح پر زیادہ تر مشکلات خدا کے مصلح کی راہ میں ڈال دیتے ہیں.وہ قرآن کے
1093
Page 1102
مکذب ہیں کہ اس کی منشاء کے برخلاف اصرار کرتے ہیں اور اپنے ایسے افعال سے جو مخالف
قرآن ہیں اور دشمنوں کے عقائد سے ہم رنگ میں دشمنوں کو مدد دیتے ہیں.پس اس طرح اُن
عُقد وں میں پھونک مار کر ان کو لا ینحل بنانا چاہتے ہیں پس ہم ان کی شرارتوں سے خدا کی پناہ
مانگتے ہیں اور نیز ہم ان لوگوں کی شرارتوں سے خدا کی پناہ مانگتے ہیں جوحسد کرتے اورحسد کے
طریقے سوچتے ہیں اور ہم اس وقت سے پناہ مانگتے ہیں جب وہ حسد کرنے لگیں.“
(تحفہ گولڑویہ، روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 221،220)
آخری مظہر شیطان کے اسم دجال کا جو مظہر اتم اور اکمل اور خاتم المظا ہر ہے وہ قوم ہے
جس کا قرآن کے اول میں بھی ذکر ہے اور قرآن کے آخر میں بھی یعنی وہ ضالین کا فرقہ جس کے
ذکر پر سورہ فاتحہ ختم ہوتی ہے.اور پھر قرآن شریف کی آخری تین سورتوں میں بھی اس کا ذکر
ہے یعنی سورۃ اخلاص اور سورہ فلق اور سورہ ناس میں
سورۃ فلق میں یہ اشارہ کیا گیا کہ یہ قوم اسلام کے لئے خطرناک ہے اور اس کے ذریعہ
سے آخری زمانہ میں سخت تاریکی پھیلے گی اور اس زمانہ میں اسلام کو ایک بڑے شر کا سامنا
ہوگا.اور یہ لوگ معضلات اور دقائق دین میں گرہ در گرہ دے کر مکار عورتوں کی طرح لوگوں کو
دھوکا دیں گے اور یہ تمام کاروبار محض حسد کے باعث ہوگا جیسا کہ قابیل کا کاروبارحسد کے
باعث تھا.فرق صرف یہ ہے کہ قابیل نے اپنے بھائی کا خون زمین پر گرایا مگر یہ لوگ بباعث
جوش حسد سچائی کا خون کریں گے.غرض سورة قُلْ هُوَ الله احد میں ان لوگوں کے عقائد کا بیان ہے اور سورہ فلق میں ان لوگوں
کے ان اعمال کی تشریح ہے جو قوت اور طاقت کے وقت ان سے ظاہر ہوں گے.چنانچہ دونوں
سورتوں کو بالمقابل رکھنے سے صاف سمجھ آتا ہے کہ پہلی سورۃ یعنی سورۃ اخلاص میں قوم نصاری
کے اعتقادی حالات کا بیان ہے اور دوسری سورۃ میں عملی حالات کا ذکر ہے.اور سخت تاریکی
سے آخری زمانہ کی طرف اشارہ ہے جبکہ یہ لوگ اس رُوح کے مظہر اتم ہوں گے جو خدا کی طرف
سے مضل ہے اور ان دونوں سورتوں کے بالمقابل لکھنے سے جلد تران لطیف اشارات کا علم ہو
1094
Page 1103
سکتا ہے.قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ کہہ میں پناہ مانگتا ہوں اُس رب کی جس نے تمام مخلوقات پیدا کی
اس طرح پر کہ ایک کو پھاڑ کر اس میں سے دوسرا پیدا کیا یعنی بعض کو بعض کا محتاج بنایا اور جو
تاریکی کے بعد صبح کو پیدا کرنے والا ہے.مِنْ شَر مَا خَلَقَ ہم خدا کی پناہ مانگتے ہیں ایسی مخلوق کی شر سے جو تمام شریروں سے شہر میں
بڑھی ہوئی ہے اور شرارتوں میں اُس کی نظیر ابتداء دنیا سے اخیر تک اور کوئی نہیں جن کا عقیدہ
امر حق لم يلد و لم یولد کے برخلاف ہے یعنی وہ خدا کے لئے ایک بیٹا تجویز کرتے ہیں.وَ مِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَ مِنْ شَيْرِ النَّقْتُتِ فِي الْعُقَدِ وَ مِنْ شَيْرِ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.اور
ہم پناہ مانگتے ہیں خدا تعالیٰ کی اس زمانہ سے جبکہ تثلیث اور شرک کی تاریکی تمام دنیا پر پھیل
جائے گی.اور نیز اُن لوگوں کے شر سے کہ جو پھونکیں مار کر گر ہیں دیں گے.یعنی دھوکادہی میں
جادو کا کام دکھائیں گے اور راہ راست کی معرفت کو مشکلات میں ڈال دیں گے.اور نیز اس
بڑے حاسد کے حسد سے پناہ مانگتا ہوں جبکہ وہ گروہ سراسر حسد کی راہ سے حق پوشی کرے گا.یہ تمام اشارات عیسائی پادریوں کی طرف ہیں کہ ایک زمانہ آنے والا ہے جو وہ دنیا میں شہر
پھیلائیں گے اور دنیا کو تاریکی سے بھر دیں گے اور جادو کی طرح ان کا دھوکا ہوگا اور وہ سخت
حاسد ہوں گے اور اسلام کو حسد کی راہ سے بنظر تحقیر دیکھیں گے.اور لفظ ربّ الْفَلَقِ اس طرف
اشارہ کرتا ہے کہ اس تاریکی کے بعد پھر صبح کا زمانہ بھی آئے گا جو مسیح موعود کا زمانہ ہے....ان دونوں سورتوں ( اخلاص اور فلق ) میں ایک ہی فرقہ کا ذکر ہے.صرف یہ فرق ہے کہ
سورۃ اخلاص میں اس فرقہ کی اعتقادی حالت کا بیان ہے اور سورۃ الفلق میں اس فرقہ کی عملی
حالت کا ذکر ہے.اور اس فرقہ کا نام سورۃ الفلق میں شَرِ مَا خَلَقَ رکھا گیا ہے.یعنی شَرُّ الْبَرِيَّةِ
اور احادیث پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ دجال معہود کا نام بھی شر الْبَرِيَّةِ ہے کیونکہ آدم
کے وقت سے اخیر تک شر میں اُس کے برابر کوئی نہیں.تحفہ گولڑو یه روحانی خزائن جلد 17 صفحه 269 - 272 حاشیہ)
1095
Page 1104
ما سورۃ فلق میں یعنی آیت وَمِن شَيرِ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ میں آنے والی ایک سخت تاریکی
سے ڈرایا گیا اور فقرہ قُل اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ میں آنے والی ایک صبح صادق کی بشارت دی گئی
اور اس مطلب کے حصول کے لئے سورۃ الناس میں صبر اور ثبات کے ساتھ وساوس سے بچنے
کے لئے تاکید کی گئی.(تحفہ گولڑویہ، روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 285 حاشیہ)
بعض لوگ اس قسم کے ہوتے ہیں کہ وہ خدا تعالیٰ کے سوا اوروں پر بھروسہ کرتے ہیں
اور کہتے ہیں اگر فلاں نہ ہوتا تو میں بلاک ہو جاتا.میرے ساتھ فلاں نے احسان کیا.وہ نہیں
جانتا کہ یہ سب کچھ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ
میں اس خدا تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں جس کی تمام پرورشیں ہیں.رب یعنی پرورش کنندہ وہی
ہے.اس کے سوا کسی کا رحم اور کسی کی پرورش نہیں ہوتی حتی کہ جو ماں باپ بچے پر رحمت
کرتے ہیں دراصل وہ بھی اسی خدا کی پرورشیں ہیں اور بادشاہ جو رعایا پر انصاف کرتا ہے اور اس
کی پرورش کرتا ہے وہ سب بھی اصل میں خدا تعالیٰ کی مہر بانی ہے.ان تمام باتوں سے اللہ تعالیٰ یہ سکھلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے برابر کوئی نہیں.سب کی
پرورشیں اسی کی ہی پرورشیں ہیں.بعض لوگ بادشاہوں پر بھروسہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ
فلاں نہ ہوتا تو میں تباہ ہو جاتا اور میرا فلاں کام فلاں بادشاہ نے کر دیا.وغیرہ وغیرہ.یادرکھو ایسا
کہنے والے کا فر ہوتے ہیں.انسان کو چاہیے کہ کا فرنہ بنے.اور مومن نہیں ہوتا جب تک کہ دل
سے ایمان نہ رکھے کہ سب پرورشیں اور رحمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں.انسان کو اس کا دوست ذرہ بھی فائدہ نہیں دے سکتا جب تک کہ خدا تعالیٰ کا رحم نہ ہو.اسی
طرح بچے اور تمام رشتہ داروں کا حال ہے.اللہ تعالیٰ کا رحم ہونا ضروری ہے.خدا تعالیٰ فرماتا
ہے کہ دراصل میں ہی تمہاری پرورش کرتا ہوں.جب تک خدا تعالیٰ کی پرورش نہ ہو تو کوئی
پرورش نہیں کرسکتا.دیکھو جب خدا تعالیٰ کسی کو بیمار ڈال دیتا ہے تو بعض دفعہ طبیب کتنا ہی زور
لگاتے ہیں مگر وہ بلاک ہو جاتا ہے.طاعون کے مرض کی طرف غور کروسب ڈاکٹر زور لگا چکے مگر
1096
Page 1105
یہ مرض دفع نہ ہوا.اصل یہ ہے کہ سب بھلائیاں اس کی طرف سے ہیں اور وہی ہے کہ جو تمام
بدیوں کو دور کرتا ہے.( البدر جلد 2 نمبر 44 مورخہ جولائی 1903 ، صفحہ 185 ، 186)
علا غاستی عربی میں تاریکی کو کہتے ہیں جو کہ بعد زوال شفق اول رات چاند کو ہوتی ہے اور
اسی لئے یہ لفظ قمر پر بھی اس کی آخری راتوں میں بولا جاتا ہے جبکہ اس کا نور جاتا رہتا ہے اور
خسوف کی حالت میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے.قرآن شریف میں مِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ
کے یہ معنے ہیں مِن شَرِ ظُلْمَةٍ إِذَا دَخَلَ یعنی ظلمت کی برائی سے جب وہ داخل ہو.( البدر جلد 2 نمبر 6 مورخہ 27 فروری 1903 ، صفحہ 43)
ا مِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ اصل میں صفات گل نیک ہوتے ہیں جب ان کو بے موقع
اور ناجائز طور پر استعمال کیا جاوے تو وہ برے ہو جاتے ہیں اور ان کو گندہ کر دیا جاتا ہے لیکن
جب ان ہی صفات کو افراط تفریط سے بچا کر محل اور موقع پر استعمال کیا جاوے تو ثواب کے
موجب ہو جاتے ہیں.قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا ہے مِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَا اور دوسری
جگہ الشبِقُونَ الْأَوَّلُونَ.اب سبقت لے جانا بھی تو ایک قسم کا حسد ہی ہے.سبقت لے
جانے والا کب چاہتا ہے کہ اس سے اور کوئی آگے بڑھ جاوے.یہ صفت بچپن ہی سے انسان
میں پائی جاتی ہے.اگر بچوں کو آگے بڑھنے کی خواہش نہ ہو تو وہ محنت نہیں کرتے اور کوشش
کرنے والے کی استعداد بڑھ جاتی ہے.سابقون گو یا حاسد ہی ہوتی ہیں لیکن اس جگہ حسد کا
مادہ مصفی ہو کر سابق ہو جاتا ہے.اسی طرح حاسد ہی بہشت میں سبقت لے جاویں گے.( البدر جلد 2 نمبر 12 مورخہ 10 را پریل 1903 ، صفحہ 89)
(ماخوذ از تفسیر حضرت مسیح موعود )
حضرت خلیفۃ اسبح الاول رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:
ملا یہ سورہ شریفہ مدنی ہے یعنی مدینہ منورہ میں نازل ہوئی تھی.اس میں بِسْمِ اللہ
1097
Page 1106
الرَّحْمٰنِ الرَّحِیم کے بعد پانچ آیتیں ہیں.اور تئیس کلمے ہیں اور تہتر حروف ہیں.اس سورۃ کے شان نزول میں بعض مفسروں نے یہ بیان کیا ہے کہ کسی یہودی نے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا اور اس قسم کے جادو گروں کے شر سے محفوظ رکھنے کے
واسطے اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھلائی ہے.اس واقعہ کو اگر احادیث میں دیکھا جائے.اول تو اس حدیث کا راوی صرف ایک شخص
ہے.یعنی ہشام.حالانکہ اتنے بڑے واقعہ کے واسطے ضروری تھا کہ کوئی اور صاحب بھی اس کا
ذکر کرتے.دوم اگر یہ واقعہ صحیح بھی ہو تو اس سے یہ نہیں ثابت ہوتا ہے کہ آنحضرت پر اس جادو کا کچھ اثر
ہو گیا تھا یا آنحضرت نے ان جادو کرنے والے لوگوں کا کچھ پیچھا کیا تھایا ان کو گرفتار کیا تھا.ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا کہ ہر زمانہ میں اور ہر ملک میں اسی قسم کے آدمی ہوا
کرتے ہیں جن کا یہ پیشہ ہوا کرتا ہے کہ وہ لوگوں پر جادو کیا کریں.اور یہ لوگ تین قسم کے
ہوتے ہیں.ایک تو وہ جو خفیہ سازشوں اور شرارتوں کے ذریعہ سے لوگوں کو سزا دیتے ہیں.مثلاً
ایک شخص ان کے پاس آیا ہے اور وہ ایک دوسرے شخص کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے.اس واسطے
ان کے پاس اپنی یہ خواہش لاتا ہے کہ میرا دشمن مرجائے یا کسی سخت بیماری میں مبتلا ہو جائے یا
مجنون ہو جائے تو وہ اس شخص کو ویسے ہی کوئی تعویذ بنا دیں گے یا کوئی تا کہ گر ہیں ڈال کر
دیدیں گے اور کہ دیں گے کہ یہ کسی طرح اپنے دشمنوں کو کھلاؤ یا اس کے گھر میں ڈال دو.یا اور
کوئی بات اس قسم کی بتلاویں گے.لیکن دراصل یہ صرف ایک ظاہری بات اس شخص کو دھوکا
دینے والی ہوگی اور خفیہ طور پر وہ اس کے دشمن کو کسی دوائی کے ذریعہ سے بیمار کرنے یا مجنون
کرنے یا بلاک کرنے پر کمر باندھیں گے.اور کسی نہ کسی حیلہ سے اس کام کو پورا کر کے اپنے
جادو گر ہونے کا لوگوں کو یقین دلائیں گے.دوسری قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو توجہ کے ذریعہ سے اس معاملہ میں کامیابی حاصل کرنا
1098
Page 1107
چاہتے ہیں اور دوسروں کو دُکھ دینے کے درپے رہتے ہیں.اس قسم کے لوگ بھی ہمیشہ دنیا میں
ہوتے رہے ہیں اور آجکل اس گروہ کی ایک بڑی جماعت امریکہ میں موجود ہے.ان کا
مطلب بھی سوائے شرارت کے اور کچھ نہیں ہوتا.اور یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے پیشہ کو مخفی رکھتے
ہیں.ورنہ گورنمنٹ ایسے لوگوں کو ہر جگہ گرفتار کر کے سزا دیتی ہے.ایسے لوگوں کی شرارتوں
سے بچنے کے واسطے انسان کو چاہئے کہ ہمیشہ ہوشیار رہے اور ہوشیاری کا سب سے عمدہ اور اعلیٰ
طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں ان کی شرارت سے پناہ مانگی جائے.اس سورۃ شریفہ سے پہلے سورۃ اخلاص ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا تذکرہ ہے.اور اس کے
ساتھ ان دوسورتوں میں اس فیضان کا تذکرہ ہے جو اللہ تعالی کی طرف سے انسان پر وارد ہوتا ہے.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر نہ ہونے کی ایک ظاہر دلیل یہ ہے کہ آنحضرت کو
مسحور کہنا تو قرآن شریف میں کفار کا قول ہے جو کہ جھوٹا قول ہے.اور نیز خدا تعالیٰ کا کلام
ہے وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ (مائده 68) پھر کس طرح ممکن ہوسکتا ہے کہ کسی یہودی کا
جاد و آنحضرت پر چل جاتا.اس جگہ یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ بیماری کے وقت بیمار کے حق میں دعا کرتے ہوئے خدا
تعالیٰ سے استعاذ کرنا طریق سنت ہے.دوا کرنا بھی ضروری ہے مگر اس کے ساتھ دعا بھی
چاہئے.چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے..حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ تمام دردوں اور
بخار کے وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو یہ دعا سکھایا کرتے تھے.اللہ کے نام کے ساتھ
جو کریم ہے.خدا عظیم کی پناہ مانگتا ہوں کبر کے شر سے اور آگ کی گرمی کے شر سے.اس طرح
خدا تعالیٰ کے حضور میں پناہ مانگنے کی دعائیں بہت سی احادیث میں وارد ہیں.اس سورۃ میں انسان کے جسمانی فوائد کے واسطے دعا ہے اور اگلی سورۃ میں روحانی فوائد
کی باتیں مندرج ہیں.یہ سورۃ بھی بجائے خود ایک جامع دعا ہے جن میں چار چیزوں سے اللہ تعالیٰ کے حضور
1099
Page 1108
میں پناہ مانگی گئی ہے.1.تمام مخلوقات کے شر سے.2 تاریکی کرنے والی اشیاء کے شر سے.3 مخالفات مخفی تدابیر کرنے والوں کے شر سے.4.حاسد کے شر سے.فقرہ اوّل میں دراصل سب شامل ہیں اور فقرہ دوم و سوم و چہارم اس کی تشریح ہیں.یعنی وہ
تمام چیزیں جو خدا تعالیٰ نے پیدا کی ہیں.ان میں جو امر اس قسم کا ہے کہ کسی انسان کے واسطے
موجب تکلیف اور دُکھ اور ضرر ہوسکتا ہے.ان سب سے خدا تعالیٰ ہم کو بچائے اور محفوظ رکھے.دنیا میں جس قدر مفاسد پیدا ہوتے ہیں وہ یا تو بہ سبب تاریکی اور ظلمت کے پھیل جانے کے
پیدا ہوتے ہیں.اور یا مخالف دشمن لوگ شرارت کے ساتھ تاریکی پیدا کرنا چاہتے ہیں.اور
فاسدلوگ از روئے حسد کے فساد مچا کر اصلیت کو چھپانا چاہتے ہیں.یہی حال ہر زمانہ میں اور
ہر نبی اور مامور کے وقت میں ہوتا ہے.آجکل بھی زمانہ میں ایک بڑی تاریکی پھیلی ہوئی
ہے اور تمام قومیں اصلیت کو چھوڑ کر گمراہی کی طرف جارہی ہیں.اس واسطے ضرورت کے موافق
خدا تعالیٰ نے اس زمانہ میں بھی ایک نور پیدا کیا ہے جو تمام ظلمات کو دور کر دیتا ہے اور مخلوق کو
ہدایت کے راہ پر لاتا ہے.اس کے مخالف چاہتے ہیں کہ حق پر پردہ ڈال دیں اور لوگوں کو
ہدایت کے حصول سے محروم رکھیں لیکن خدا تعالیٰ اپنی باتوں کو پورا کرے گا اور اپنے بندے کی
صداقت کو روز روشن کی طرح نمایاں کرنا اُسی خدائے قادر کا کام ہے جس کو کوئی روک نہیں سکتا.اس سورۃ شریفہ میں جو قرآن شریف کی آخری سورتوں میں سے ہے اس امر کی طرف
اشارہ ہے کہ آخری زمانہ میں ایک بڑا فتنہ ہوگا.ایک بہت بڑ اشتر اُٹھے گا اور وہ ایسے وقت میں
ہوگا جبکہ اللہ تعالیٰ زمانہ میں تاریکی کو دور کرنے کے واسطے ایک صبح کو نمودار کرے گا.کیونکہ وہ
رَبُّ الفلق ہے اور رات کے بعد دن کو لاتا ہے اور تاریکی کے بعد نور پیدا کرتا ہے.اس شئر
1100
Page 1109
سے بچنے کے واسطے تمام مسلمانوں کو ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہئے کیونکہ وہ بڑا بھاری شٹر ہے.اُس شر کا پیدا کرنے والا خفیہ کارروائیاں بہت کرے گا اور چھپ چھپ کر اپنی سازشیں دین حق
کے برخلاف نہایت جد و جہد کے ساتھ کرے گا.چنانچہ ظاہر ہے کہ جس قدر خفیہ کارروائیاں مشن کا دجال اسلام کے برخلاف کرتا ہے ایسی
کارروائیاں پہلے کبھی کسی نے نہیں کیں.ایسے ایسے راہوں سے اسلام پر حملہ کرنے کے واسطے
کوشش کی جاتی ہے کہ عوام تو سمجھ بھی نہیں سکتے کہ اس معاملہ میں کیا در پردہ شرارت ہے لیکن
خدا تعالیٰ نے اس زمانہ میں ایک ایسا نور پیدا کیا ہے جس نے نمودار ہو کر ان تمام پردوں کو
پھاڑ دیا ہے اور دنبال کا دجل کھول کر لوگوں کو دکھا دیا ہے تا کہ مخلوقِ الہی اس کے شر سے بچی
رہے.اور اس کے پھندے میں نہ آئے.افسوس ہے اُن لوگوں پر جو خدا تعالیٰ کے اس نور کو
اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں.وہ یاد رکھیں کہ یہ نو ر الہی ضرور غالب آئے گا اور اس
کے مخالف سب نامراد اور نا کام مریں گے.چار قل جو نماز میں اور نماز کے بعد پڑھے جاتے ہیں ان میں سے یہ تیسرا قتل ہے.قرآن شریف میں فلق کا لفظ تین طرح پر استعمال ہوا ہے.فَالِقُ الْإِصْبَاحِ فَالِقُ الْحَبْ وَ
النّوى - پس خدا فَالِقُ الْإِصْبَاحِ فَالِقُ الْحَت اور فَالِقُ النّوى ہے.دیکھو رات کے
وقت خلقت کیسی ظلمت اور غفلت میں ہوتی ہے.بجز موذی جانوروں کے عام طور سے
چرند پرند بھی اس وقت آرام اور ایک طرح کی غفلت میں ہوتے ہیں.آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے تاکیدی حکم دیا ہے کہ رات کے وقت گھروں کے دروازے بند کر لیا کرو.کھانے
پینے کے برتنوں کو ڈھانک رکھا کرو.خصوصا جب اندھیرے کی ابتدا ہو اور بچوں کو ایسے
اوقات میں باہر نہ جانے دو کیونکہ وہ وقت شیاطین کے زور کا ہوتا ہے.رات کی ظلمت میں عاشق اور معشوق.قیدی اور قید کنندہ.بادشاہ اور فقیر.ظالم اور مظلوم
سب ایک رنگ میں ہوتے ہیں اور سب پر غفلت طاری ہوتی ہے.ادھر صبح ہوئی اور جانور بھی
پھڑ پھڑانے لگے.مُرغے بھی آوازیں دینے لگے.بعض خوش الحان آنے والی صبح کی خوشی میں
1101
Page 1110
اپنی پیاری راگنیاں گانے لگے.غرض انسان حیوان ، چرند، پرند،سب پر خود بخود ایک قسم کا اثر
ہو جاتا ہے اور جوں جوں روشنی زور پکڑتی جاتی ہے توں توں سب ہوش میں آجاتے ہیں.گلی،
کوچے، بازار، دکانیں، جنگل، ویرانے سب جو کہ رات کو بھیا نک اور سُنسان پڑے تھے.ان میں چہل پہل اور رونق شروع ہو جاتی ہے.گویا یہ بھی ایک قسم کی قیامت اور حشر کا نظارہ ہوتا
ہے.خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ فالق الاصباح میں ہوں.اس چھوٹی سی سورۃ میں اللہ تعالیٰ نے لفظ فلقی کے نیچے باریک در بار یک حکمتیں رکھی
ہیں اور انسان کو ترقی کی راہ بتائی ہے کہ دیکھو جب کوئی چیز میرے قبضہ قدرت اور ربوبیت
کے ماتحت آجاتی ہے تو پھر وہ کس طرح ادنی اور ارذل حالت سے اعلیٰ اور اعلیٰ بن جاتی ہے.پس انسان کو لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ان صفات کو مد نظر رکھ کر اور اس کی کامل قدرت کا یقین کر
کے اور اس کے اسماء اور صفات کا ملہ کو پیش نظر رکھ کر اس سے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ ضرور اسے
بڑھاتا اور ترقی دیتا ہے.مِن شَرِّ مَا خَلَقَ مخلوقِ الہی میں بعض چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ بعض اوقات انسان
کے واسطے مضر ہو جاتی ہیں اُن سے بھی اللہ تعالیٰ ہی بچا سکتا ہے کیونکہ وہ بھی خدا ہی کے
قبضہ قدرت میں ہیں.وَمِن شَرِ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ اور اندھیرے کے شر سے جب وہ بہت اندھیرا کر
دیوے.ہر اندھیرا ایک تمیز کو اٹھاتا ہے.جتنے بھی موذی جانور ہیں.مثلاً مچھر، پتو،کھٹمل،
مجوں، ادنی سے اعلیٰ اقسام تک کل موذی جانوروں کا قاعدہ ہے کہ وہ اندھیرے میں جوش
مارتے ہیں اور اندھیرے کے وقت ان کا ایک خاص زور ہوتا ہے.ظلمت بھی بہت قسم کی
ہے.ایک ظلمت فطرت ہوتی ہے.جب انسان میں ظلمت فطرت ہوتی ہے تو اس کو ہزار
دلائل سے سمجھاؤ اور لاکھ نشان اس کے سامنے پیش کرو وہ اس کی سمجھ میں ہی نہیں آسکتے.ایک
ظلمت جہالت ہوتی ہے.ایک ظلمت عادت.ظلمت رسم _ ظلمت صحبت _ ظلمت معاصی.غرض یہ سب اندھیرے ہیں.دعا کرنی چاہئے کہ اللہ تعالیٰ ان سب سے محفوظ رکھے.1102
Page 1111
وَمِنْ شَرِ النَّقْفْتِ فِي الْعُقَدِ اس قسم کے شریر لوگ بہت خطرناک ہوتے ہیں.میں
نے اس قسم کے لوگوں کی بہت تحقیقات کی ہے اور اس میں مشغول رہا ہوں اور طب کی وجہ سے
ایسے لوگوں کو بھی میرے پاس آنے کی ضرورت پڑی ہے اور میں نے ان لوگوں سے دریافت
کیا ہے.ان لوگوں کو خطرناک قسما قسم کے زہر یاد ہوتے ہیں جن کے ذریعہ سے بعض
امراض انسان کے لاحق حال ہو جاتی ہیں.وہ زہر یہ لوگ بار یک در بار یک تدابیر سے
خادماؤں یا چوہڑیوں کے ذریعہ سے لوگوں کے گھروں میں دفن کرا دیتے ہیں.آخر کار ان کے
اثر سے لوگ بیمار ہو جاتے ہیں.پھر ان کے چھوڑے ہوئے لوگ مرد اور عورتیں ان بیماروں کو
کہتے ہیں کہ کسی نے تم پر جادو کیا ہے.کسی نے تم پر سحر کیا ہے.لہذا اس کا علاج فلاں شخص
کے پاس ہے.آخر مرتا کیا نہ کرتا.لوگ ان کی طرف رجوع کرتے ہیں اور یہ لوگ اپنی
مستورات کے ذریعہ سے چونکہ ان کو علم ہوتا ہے کہ وہ زہر کہاں مدفون ہے اور ان کے پاس
ایک باقاعدہ فہرست ہوتی ہے.وہ زہر مدفون نکال کر اُن کو بتاتے ہیں اور اس طرح سے ان
بیماریوں کا اعتقاد اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے.پھر ان لوگوں کو چونکہ ان زہروں کے تریاق بھی یاد
ہوتے ہیں.ان کے استعمال سے بعض اوقات تعویذ کے رنگ میں لکھ کر پلوانے سے یا کسی
اور ترکیب سے ان کا استعمال کراتے ہیں اور اُن سے ہزاروں روپے حاصل کرتے ہیں.اس
طرح سے بعض کو کامیاب اور بعض کو ہلاک کرتے ہیں.ایک تو یہ لوگ ہیں جولوگوں کو اپنے
فائدے کی غرض سے
قسم قسم کی ایذائیں پہنچاتے ہیں.دوسری قسم کے وہ شریر لوگ ہیں جو مومنوں کے کاروبار میں اپنی بد تدابیر سے روک اور حرج
پیدا کرتے ہیں اور اس طرح سے پھر مومنوں کی کامیابی میں مشکلات پیدا ہو جاتے ہیں.مگر
آخر کار وہ نا کام رہ جاتے ہیں.اور مومنین کا گروہ مظفر ومنصور اور بامراد ہوجاتا ہے.وَ مِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ - کسی کی عزت، بھلائی، برائی ، بہتری،اکرام اور
جاہ و جلال کو دیکھ کر جلنے والے لوگ بھی بڑے خطرناک ہوتے ہیں کیونکہ وہ بھی انسانی ارادوں
میں بوجہ اپنے حسد کے روک پیدا کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں.1103
Page 1112
غرض یہ سورۃ مشتمل ہے ایک جامع دعا پر.رسول اکرم نے اس سورۃ کے نزول کے بعد
بہت سے تعوذ کی دعائیں ترک کر دی تھیں اور اسی کا ورد کیا کرتے تھے.حتی کہ بیماری کی
حالت میں بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس سورۃ کو آپ کے دستِ مبارک پر پڑھ کر
آپ کے منہ اور بدن پر ملتی تھیں.مگر افسوس کہ مسلمانوں نے عام طور سے اب ان عجیب
پُر تا ثیر اؤ راد کو قریبا ترک کر دیا ہے.بعض کا قول ہے کہ شر ما خلق سے مراد شیطان ہے کیونکہ اس سے بڑھ کر کوئی شے
انسان کے واسطے موجب شر اور دُکھ اور تکلیف نہیں.ایک قول یہ ہے کہ شر ما خلق سے مراد
جہنم ہے گویا کہ انسان خدا تعالیٰ کے حضور جہنم سے پناہ چاہتا ہے.بہر حال اس میں تمام موذی
اور دُکھ دینے والے اور خدا سے دور رکھنے والی اشیاء سے خدا کے حضور پناہ مانگی گئی ہے.خواہ وہ
شیطان ہو یا جن یا موذی حیوان مثل بچھو، سانپ ، شیر وغیرہ.ناسق :اندھیرا کرنے والا.ہر ایک چیز جو تاریکی اور ظلمت پیدا کرے.فاسق رات کو
کہتے ہیں اور شمسق تاریکی کو کہتے ہیں کیونکہ رات تاریکی پیدا کرتی ہے.اس واسطے وہ فاسق
ہے.اور غسق برد کو بھی کہتے ہیں.کیونکہ رات بہ نسبت دن کے ٹھنڈی ہوتی ہے.فاسق ثریا
کو بھی کہتے ہیں.کیونکہ اس کا گرنا عموما و با اور بیماریوں کا پیش خیمہ ہوتا ہے.اور غاسق سورج
کو بھی کہتے ہیں جبکہ غروب ہو جاوے اور چاند کو بھی کہتے ہیں جبکہ اس کو گہن لگے.فاسق سانپ
کو بھی کہتے ہیں جبکہ وہ کاٹ کھائے اور ہر ایک نا گہاں آنے والی چیز جو ضرر پہنچائے.یا
بھیک مانگنے والا جبکہ وہ تنگ کرے تو اس کو بھی فاسق کہتے ہیں.غرض ہر ایک چیز جو انسان کو
ظلمت روحانی یا جسمانی میں ڈالے اس کو عماسق کہتے ہیں.جب رات بہت تاریک ہو تو عرب
کے محاورہ میں کہتے ہیں غَسَقَ اللَّيْلُ.اور جب آنکھیں آنسوؤں سے بھر جائیں تو کہتے ہیں
غَسَقَتِ الْعَيْنُ اور جب زخم پیپ سے بھر جائے تو کہتے ہیں غَسَقَتِ الْجَرَاحَةُ
وقب : کے معنے ہیں چھپ گیا.وقت کے اصلی معنی ہیں کسی شے میں داخل ہونا ایسا کہ وہ
نظر سے غائب ہو جاوے.1104
Page 1113
التقلب في العقد :
گر ہوں میں پھونکنے والیاں.التَّقْفتِ التَّفْعُ وَمَعَ رِيقٍ نَفَفْ کے معنے ہیں پھونکنا جن
میں تھوک بھی ہو.گرہ میں پھونکنا جیسا کہ جادو گرلوگ تا گوں میں گر میں ڈال کر پھونکتے ہیں.اور لوگوں کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ اس کا اثر ہوتا ہے.گرہ میں پھونکنا اور گرہ دینا یہ ایک محاورہ ہے جس کے معنی ہیں کسی کام میں رکاوٹ ڈالنے
کے واسطے کوشش کرنا جیسا کہ وہ لوگ جو جادوگری کا پیشہ رکھتے ہیں اپنی جھوٹی جادوگری میں
کامیابی حاصل کرنے کے واسطے خفیہ تدابیر کرتے ہیں.ظاہر تو کرتے ہیں کہ فلاں آدمی کو ہم
نے جادو کے ذریعہ سے بیمار کر دیا ہے اور دراصل کسی خفیہ ذریعہ سے اس قسم کی دوائیاں اس
شخص کو کھلا دیتے ہیں جن سے وہ بیمار ہو جائے.پس ایسے خفیہ شریرلوگوں کی شرارت سے بچا
رہنے کے واسطے اللہ تعالیٰ کے حضور میں ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہئے.حاسد وہ ہے جو خواہش کرے کہ دوسرے کے پاس جو عمدہ شے ہے وہ اس کو مل جاوے.بسا اوقات اس حسد میں اس شخص کو نقصان پہنچانے کی بھی خواہش اور کوشش کرتا ہے جس کو
اس نعمت کا مالک دیکھتا ہے.لفظ حاسد کو اس جگہ نکرہ رکھا ہے.معرفہ نہیں رکھا.اس میں یہ حکمت ہے کہ حسد ہمیشہ بُرا
نہیں ہوتا بلکہ اگر نیکیوں کے حصول کے واسطے حسد کیا جائے تو وہ حسد محمود ہے.ماخوذ از حقائق الفرقان.زیر تفسیر سورۃ الفلق )
حضرت خلیفہ المسیح الثانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں :
عملا مسلم ترمذی اور نسائی میں روایت آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب
سورۃ الفلق اور سورۃ الناس نازل ہوئیں تو حضور نے فرمایا کہ آج رات مجھ پر ایسی بے مثل
آیات اُتاری گئی ہیں کہ ان جیسی پہلے نازل نہیں ہوئیں.اور پھر اس کے بعد سورۃ الفلق اور
1105
Page 1114
سورۃ الناس پڑھیں.یہ سورتیں چونکہ ایک طرف قرآن کریم کا خلاصہ ہیں اور دوسری طرف ان میں مضامین کی
کثرت ہے اور بعض آئندہ زمانہ کے متعلق پیشگوئیاں بھی ہیں.اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کا یہ فرمانا کہ یہ سورتیں بے مثل ہیں.یہ ان کے فضائل اور کثرت مضامین کی طرف اشارہ ہے.بخاری.ابوداؤد.نسائی اور ابن ماجہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کے وقت اپنے بستر میں آرام فرماتے تو اپنی دونوں ہتھیلیوں
کو جمع کرتے اور اور سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی تلاوت فرماتے اور ہتھیلیوں
میں پھونکتے اور سر سے لے کر پاؤں تک سارے جسم پر مل لیتے اور یہ فعل تین بار کرتے.نیز حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جو شخص ان دونوں سورتوں کو سورۃ الاخلاص کے ساتھ ملا کر
صبح و شام پڑھے گا اس کے لئے یہ کافی ہو جائیں گی اور اس کی ضرورت پوری ہوگی اور دُکھ درد
سے محفوظ رہے گا.اس سے مراد یہ ہے کہ قرآنی تعلیم انسان کو دُکھوں سے بچاتی ہے.کیونکہ جو
شخص صبح و شام معوذتین پڑھے گا لاز ما قرآنی تعلیم خلاصۂ صبح وشام اس کے سامنے آتی رہے
گی اور جس کے سامنے صبح و شام قرآنی تعلیم آتی رہے گی اُسے عمل کا بھی خیال آئے گا.اور اس
طرح وہ دُکھوں سے بھی محفوظ رہے گا.اسی طرح عقبہ بن عامر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اقْرَءُوا
بِالْمُعَوَّذَاتِ فِي دُبُرِ كُلّ صَلوة (در منثور) یعنی اے لوگو! ہر نماز کے بعد سورۃ الفلق اور سورۃ
الناس کو پڑھا کرو.اسی طرح سے حضرت اُم سلمہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
مِنْ أَحَبّ السُّوَرِ إِلَى اللهِ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ کہ اللہ تعالیٰ کو
سب سے زیادہ پسند یہ دوسورتیں ہیں.یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس.پھر یہ روایت بھی آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الاخلاص اور معوذتین کو ملا کر
وتر کی آخری رکعت میں پڑھا کرتے تھے.( ڈرمنثور )
1106
Page 1115
یہ سب روایات ان سورتوں کے فضائل کو ظاہر کرتی ہیں اور ہمیں اس طرف راہنمائی کرتی
ہیں کہ ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ پر نگاہ رکھنی چاہئے اور اس کی پناہ میں رہنے کی دعا کرتے رہنا
چاہئے.وتر کی آخری رکعت چونکہ دن کی نمازوں کے خاتمہ پر ہوتی ہے اس لئے رسول کریم
صلی اللہ علیہ وسلم اس میں یہ دونوں سورتیں ملا کر پڑھتے تھے.اور آپ کا یہ فرمانا کہ جو شخص صبح و
شام ان سورتوں کو پڑھے گا وہ آفات سے محفوظ ہو جائے گا.اس کے معنے یہ ہیں کہ انسان کو اپنی
ابتدا بھی قرآنی تعلیم پر رکھنی چاہئے اور اپنی انتہا بھی قرآنی تعلیم پر رکھنی چاہئے.م سورة اخلاص میں توحید کامل کا سبق سکھایا گیا ہے.اور بتایا گیا ہے کہ سارے قرآن
مجید کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں.پھر اس کے بعد سورۃ الفلق
اور سورۃ الناس میں ہر مسلمان کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنے اپنے زمانہ میں خدا تعالیٰ کی توحید
کے جھنڈے کو بلند رکھے.اور کسی جابر ظالم اور دشمن اسلام سے ڈرے نہیں.اور یہ یقین رکھے
کہ صرف ایک خدا تعالیٰ کی ہستی ہی ہے جس کے اشارہ پر ساری کائنات حرکت کرتی ہے اور
وہ خدا ہر خیر کے دینے اور ہر شر سے محفوظ رکھنے پر قادر ہے.پس اس کی توحید کا اعلان کرنے
کے لئے مخلوق میں سے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں.کیونکہ جب کوئی شخص تو حید کی
اشاعت کے لئے کھڑا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کی خود حفاظت کرے گا.اور بڑے سے بڑا بادشاہ بھی
اس کا مقابلہ نہ کر سکے گا.سورة الفلق کا تعلق سورۃ نضر سے بھی ہے.سورۃ نصر میں اللہ تعالیٰ نے یہ خبر محمد
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی کہ اسلام بڑھے گا، پھولے گا اور پھلے گا اور کوئی اس کی ترقی
کو روک نہیں سکتا.سورۃ الفلق میں یہ بتایا کہ اے مسلمانو! جب تمہیں خدا تعالیٰ کی پیشگوئیوں
کے مطابق غلبہ مل جائے تو تم اللہ تعالیٰ کے حضور جھک جانا اور دعا کرنا کہ تمہارے اندر کوئی
ضعف پیدا نہ ہو اور تمہارا سورج کبھی ڈوبنے نہ پائے بلکہ نصف النہار پر چمکتا ر ہے.اور کسی
قسم کا شر پیدا نہ ہو.اور نہ تو تمہارا اندرونی نظام درہم برہم ہو کر تمہارا شیرازہ بکھرے اور نہ کوئی
بیرونی حاسد کھڑا ہو جائے اور تمہاری حکومت کو تباہ کر دے.1107
Page 1116
لفظ الفلق کے مختلف لغوی معانی کو سامنے رکھتے ہوئے قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ کے
معنے ہوں گے :
1.میں اس خدا کی پناہ چاہتا ہوں جو اندھیرے کے بعد روشنی پیدا کرتا ہے.2.میں اس خدا کی پناہ چاہتا ہوں جس نے سب کچھ پیدا کیا ہے.یا جس نے جہنم کو پیدا
کیا ہے.یا جس نے دو گھاٹیوں کے درمیان ایک عمدہ میدان بنایا ہے.( یعنی اسلام جو افراط
و تفریط کے درمیان ہے.)
3.یا ئیں اس خدا کی پناہ میں آتا ہوں جس کا اقتدار قید خانوں پر بھی ہے.4.اس خدا کی پناہ چاہتا ہوں جو نہروں کا رب ہے.5.اس خدا کی پناہ چاہتا ہوں جس کے قبضے میں پیالے کا بچا ہوا دودھ ہے.سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو معوذتان کہتے ہیں.یعنی وہ سورتیں جن کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ
کی پناہ طلب کی جاتی ہے.اور ان
کا یہ نام اس وجہ سے رکھا گیا ہے کہ ان دونوں کے ابتدا میں
قُلْ اَعُوذُ کے الفاظ رکھے گئے ہیں.یعنی ہر پڑھنے والے کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ یہ اعلان
کرے کہ میں ہر قسم کے شر سے بچنے کے لئے رب الفلق اور رب الناس کی پناہ میں آتا ہوں.قومی لحاظ سے اور فردی لحاظ سے بھی.قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ.یعنی اے
قرآن کریم کے ماننے والے جب تو قرآن کو پڑھنے کا ارادہ کرے تو اللہ تعالیٰ سے استعاذہ کرلیا
کر.پس قرآن کریم کے شروع کرتے وقت آغوذ پڑھنے کا حکم تو دیالیکن قرآن کریم کے
شروع میں آعُوذُ نازل نہیں کیا.قرآن کریم کی ابتدا کرتے وقت صرف اتنا ہی حکم دیا کہ
آغوذ پڑھ لیا کرو.اور اس آغوذ کے جو الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں وہ بہت
ہی مختصر ہیں.گویا قرآن کریم کے پڑھنے والے کی ذہنی کیفیت کے مطابق ہیں.اور قرآن کریم
کے آخر میں جو آغوذ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے وہ بہت زیادہ وسیع مطالب پر حاوی ہے
1108
Page 1117
اور اس میں مضرات سے بچنے کے لئے کامل دعا سکھائی گئی ہے.اور یہ اس شخص کی ذہنی
کیفیت کے مطابق ہے جو سارے قرآن کریم کو پڑھ لیتا ہے.اور ہر اونچ نیچ کا اسے علم ہو جاتا
ہے اور سمجھ لیتا ہے کہ مجھے فلاں فلاں چیز سے بچنا چاہئے اور فلاں فلاں قسم کی چیز کا طالب ہونا
چاہئے.پس ہر دو اعوذ خاص حکمتوں پر مشتمل ہیں.پھر قرآن مجید کے ابتدا میں آعُوذ پڑھنے کا حکم دینے اور آخر میں آعُوذُ نازل کرنے میں
اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ دنیوی امور کا تو کیا ذکر ہے دینی امور کی ابتدا بھی اللہ
تعالی کی پناہ سے ہونی چاہئے اور ان امور کی انتہا بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ پر ہونی چاہئے.کیونکہ کوئی
شخص کتنا ہی دینی معاملات میں دسترس رکھتا ہو اور کتنا ہی اللہ تعالیٰ کا عرفان اسے حاصل ہو
اللہ تعالیٰ کی نصرت اور اس کی حفاظت سے مستغنی نہیں ہو سکتا...بگر باوجود اس کے کہ
مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ وہ ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کے آستانہ پر جھکے رہیں اور اس سے
اس کی اعانت طلب کرتے رہیں.اگر وہ چند دن بھی نیکی کا کوئی کام کرتے ہیں تو کبر اور خود
پسندی میں مبتلا ہو جاتے ہیں.تھوڑے دن نمازیں پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ پر احسان جتانے
لگ جائیں گے.چند روزے رکھیں گے تو سمجھ لیں گے کہ اب خدا تعالیٰ پر احسان ہو گیا اور اب
اس کا فرض ہو گیا ہے کہ وہ ان کی خواہش پوری کرے.چندہ دیا تو اس وہم میں مبتلا ہونے لگیں
گے کہ اب خدا تعالیٰ پر ان کا حق قائم ہو گیا ہے اور اگر وہ کوئی امتیازی سلوک ان سے نہیں کرتا
تو نعوذ باللہ مجرم ہے.یہی چیزیں ہیں جو انسان کو تباہ کر دیتی ہیں.اور جب کسی کے اندر یہ روح
پیدا ہو جائے تو چاہے وہ ترقی کے تمام مدارج طے کر چکا ہو اس کے اعمال حبط ہو جاتے
ہیں اور وہ ادنیٰ سے ادنی مقام پر پہنچ جاتا ہے.پس انسان کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے
رہنا چاہئے تاوہ کسی موقعہ پر بھی کبر میں مبتلا ہو کر اللہ تعالیٰ کے انعامات سے محروم نہ ہو جائے.کبر ابتدا میں بھی انسان کو نیکی سے محروم رکھتا ہے یعنی جب اس کے سامنے کوئی بات پیش کی
جائے تو وہ اسے سُن نہیں سکتا.اور کبر انتہا میں بھی انسان کی ہلاکت کا باعث بنتا ہے کیونکہ
1109
Page 1118
انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اب وہ ایسے مقام پر پہنچ چکا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت
نہیں.قرآن کریم کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے آغو ذرکھا ہے اور اس طرح یہ نصیحت کی ہے کہ
دیکھو تم نے قرآن کریم کو پڑھا، اس پر غور کیا، اس کے مطالب کو سمجھا اور روحانیت میں ترقی
حاصل کی.لیکن یاد رکھو جہاں تم نے یہ سمجھا کہ اب اس کے بعد تمہیں دوسروں پر کوئی فوقیت
حاصل ہوگئی ہے اور تم کبر میں مبتلا ہو گئے وہی تمہاری تباہی کا دن ہو گا.اس لئے جب بھی تم کوئی
دینی یادنیوی کام کرو خدا تعالیٰ کی طرف نظر رکھو.اور جب اس کام
کو ختم کر لو تب بھی خدا تعالیٰ پر نظر
رکھو.اس میں یہ پیشگوئی بھی معلوم ہوتی ہے کہ مسلمان آخری دنوں میں اپنی فتوحات پر جو اُن کو
خدا تعالیٰ کی طرف سے ملیں گی متکبر ہو جائیں گے اور اس کے نتیجہ میں پھر طرح طرح کی تباہیاں
ان پر نازل ہونی شروع ہو جائیں گی.پس ان کو چاہئے کہ سُورَةُ الفَلَقِ اور سُورَةُ الناس پڑھتے
رہا کریں تا کہ اللہ تعالیٰ ان کو تکبر سے بھی بچائے اور دلی وساوس سے بھی بچائے تا کہ وہ دشمن
کے حملہ سے محفوظ ہوجائیں.ایک لطیف بات جو یاد رکھنے کے قابل ہے یہ ہے کہ اَعُوذُ کے لفظ سے پہلے قُل کا
لفظ لایا گیا ہے.قل کے بعد اعُوذُ لانے کا یہ مطلب ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس حکم کے
مخاطب ہیں.اور آعُوذُ کہنے میں محمد رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اول المخاطبین ہے.جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ کہلوایا کہ تم لوگوں کو کہ دو کہ
میں جس مقام ترقی پر پہنچ چکا ہوں اس کے باوجود میں بھی رَبُّ القلق کی پناہ مانگتا ہوں.تو امتِ
مسلمہ کے افراد اعُوذُ کی اہمیت کو زیادہ عمدگی سے سمجھ سکتے تھے.اس عظیم الشان انسان کے منہ سے اَعُوذُ کہلوا کر جو کمالات روحانیہ کا نقطۂ مرکزی ہے اس
1110
Page 1119
آپ
کی اہمیت کو زیادہ کیا گیا ہے کہ جب خدا تعالیٰ کا نبی بھی آغوذ کا محتاج ہے تو تم کیوں نہیں.بے شک ایک عام انسان تو اس لئے آعُوذُ پڑھتا ہے کہ وہ شیطان سے پناہ میں رہے
اور جب وہ اَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّحِیم کہتا ہے تو وہ اپنے گناہگار ہونے کا بھی
اعتراف کر لیتا ہے.لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آعُوذُ پڑھنا ان معنی میں نہیں ہوسکتا کیونکہ
معصوم ہیں.اس لئے قرآن کریم میں ان سورتوں کو قُل کے ساتھ شروع کیا گیا اور اس
طرف اشارہ کیا گیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گناہوں کو دیکھ کر آعُوذُ نہیں پڑھتے
تھے بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کے لئے پڑھتے تھے تا کہ آئندہ آپ کے اور آپ کی
جماعت کے خلاف شیطان کوئی کارروائی نہ کر سکے.حمد سورۃ الفلق اور سورۃ الناس دونوں سے پہلے آغوذ کا لفظ رکھا گیا ہے.گویا دونوں
سورتیں استعاذہ کے مضمون کو لے کر آئی ہیں.یعنی خدا تعالیٰ سے انسان پناہ طلب کرتا ہے.ما سورۃ الفلق میں زیادہ تر انسان کے سوا دوسری مخلوقات کی بُرائیوں سے بچنے کی دعا
سکھائی گئی ہے اور سورۃ الناس میں زیادہ تر ان فتنوں سے بچنے کی دعا سکھائی گئی ہے جن کی ابتدا
انسانوں سے ہو.اور چونکہ یہ دونوں مضمون علیحدہ علیحدہ ہیں اس لئے ان کو علیحدہ علیحدہ سورتوں
میں بیان کیا گیا ہے.مسلمانوں کو دعا سکھائی کہ تم ان جملہ اشیاء کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہو جو اس نے
پیدا کی ہیں.گویا مِن شَرِ مَا خَلق میں یہ اشارہ ہے کہ مسلمانوں کو ہر چیز ملے گی کیونکہ اس میں
ہر چیز کے شرسے بچنے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے.اور ہر چیز کے شر سے بچنے کی ضرورت اسے
ہی ہوسکتی ہے جسے ہر چیز حاصل بھی ہو.قُل اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ میں قومی دعا کے علاوہ فردی طور پر بھی کمال تک پہنچنے کے لئے
دعا سکھائی گئی ہے.چنانچہ رب کے معنے ہیں وہ ہستی جو انسان کو تدریجا ترقی دیتے دیتے کمال
تک پہنچاتی ہے.گویا قُل اَعُوذُ بِرَبِ الْفَلَقِ میں مضمون یہ ہے کہ اے خدا جو ظلمت کے بعد
1111
Page 1120
روشنی کو لاتا ہے مجھے بھی ظلمت سے نکال کر روشنی میں لا.یہ ظاہر ہے کہ اندھیرے میں پو پھٹتی
ہے اور آہستہ آہستہ روشنی ہوتی جاتی ہے اور سورج او پر آتا جاتا ہے حتی کہ نصف النہار پر چمکنے
لگتا ہے.پس فرمایا: اے وہ رب جس نے تمام ذاتی کمالات اور ترقی کے سامان جس قدر کہ
ضروری تھے انسان میں جمع کر دیتے ہیں اور بتا دیا ہے کہ انسان اپنی ذات کو ان ذرائع کے
استعمال سے کس طرح مکمل کر سکتا ہے.اے اپنی ذات میں کامل خدا مجھ کو بھی کمالات حاصل
کرنے کی توفیق دے.اور مجھ کو اپنی صفت ربوبیت کے ماتحت اس طور پر کمال دے کہ میں
بھی اسی طرح دنیا میں چھکوں جس طرح سورج وسط آسمان پر چمکتا ہے.اور مجھے ہر قسم کے دُکھ
اور مصیبت سے محفوظ رکھ.اور کمال کے حصول میں کوئی مانع نہ ہو.فلق کے دوسرے معنے ہیں الْخَلْقُ كُلُّهُ.یعنی تمام مخلوقات.پس قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ
الْفَلَقِ کے معنی ہوں گے میں اس خدا کی پناہ چاہتا ہوں جو تمام مخلوقات کا رب ہے.یعنی جوہر
چھوٹی بڑی چیز کا پیدا کرنے والا ہے.اس آیت میں مخلوقات کے مفہوم کو ادا کرنے کے لئے لفظ فلق کو اختیار کیا گیا ہے اور
خلق کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا.کیونکہ خلق کی نسبت فلق میں ایک زائد مفہوم پایا جاتا ہے.خلق کا لفظ صرف پیدائش پر دلالت کرتا ہے.مگر فلق کا لفظ ادنی سے اعلیٰ حالت کی طرف
جانے پر بھی دلالت کرتا ہے.پھر فلق کے معنے تاریکی سے روشنی کی طرف جانے کے بھی
ہیں.اسی لئے فلق صبح کو بھی کہتے ہیں.پس ایک تاریک چیز جب روشنی کی طرف جاتی ہے تو
اسے فلق کہتے ہیں.خالی تخلق کا لفظ اگر کہا جاتا تو اس میں یہ اشارہ نہ ہوتا کہ انسانی پیدائش کو
اونی حالت سے اعلیٰ حالت میں منتقل کرنے کا ذکر ہے.لیکن فلق کہہ کر بتا دیا کہ مخلوق کی
حالت پہلے ادنی ہوتی ہے جسے اللہ تعالیٰ اعلیٰ بنا دیتا ہے.پس آعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ میں جہاں
اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے وہاں پناہ مانگنے کے اسباب بھی بتا دیئے ہیں.یعنی ہم
اس سے پناہ مانگ سکتے ہیں جو اشیاء کا خالق و مالک ہو اور جو نقصان رساں چیزوں سے محفوظ
1112
Page 1121
رکھ کر ترقیات کے بلند مقام پر پہنچا سکتا ہے.مِنْ شَرِّ مَا خَلق جو چیز بھی اس نے پیدا کی ہے اس کے شر سے میں اس کی پناہ چاہتا
ہوں.اس میں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں جس میں سے شر نہ پیدا
ہو سکے.عام طور پر لوگ خیال کر لیتے ہیں کہ بعض چیزیں اچھی ہیں اور بعض بُری.مگر قرآن
کریم بتاتا ہے کہ یہ بیچ نہیں.ہر چیز اچھی بھی ہے اور ہر چیز بری بھی ہے.کوئی اچھی بات نہیں
جس میں شر نہ ہو اور کوئی بری بات نہیں جس میں خیر نہ ہو.مثلا غربت و امارت ہے.اگر اللہ تعالیٰ کا
فضل نہ ہو تو دولت بھی شر پیدا کرسکتی ہے اور اگر فضل ہو تو غربت بھی کوئی شر پیدا نہیں کرسکتی.شر در حقیقت اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب انسان خدا تعالیٰ کی حفاظت سے باہر نکل جائے.قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ میں خدا تعالیٰ نے یہی بتایا ہے کہ یہ نہ کہا کرو کہ یہ بُری چیز
ہے مجھ سے دور رہے اور فلاں اچھی چیز ہے مجھے مل جائے کیونکہ بُری چیز کی برائی اور اچھی چیز کی
خوبی سب آغوڈ سے دوری اور نزدیکی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے.اگر آعُوذُ نہ ہو تو اچھی چیز بھی بری
بن جاتی ہے.اور اگر آخوذ کا سہار ا ساتھ ہو تو بری چیز بھی خیر کا موجب بن جاتی ہے.پس قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ میں انسان کو اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کی
حفاظت کی طرف متوجہ کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ اگر مخلوقات کے برے پہلو سے تم بچنا
چاہو تو صرف اللہ تعالیٰ ہی تمہیں بچا سکتا ہے.کیونکہ وہ تمام مخلوقات کا رب ہے اور جانتا ہے کہ
کس طرح ہر شر سے بھی خیر پیدا ہوسکتا ہے اور مخلوقات میں سے کوئی شے اس کے اذن کے بغیر
حرکت نہیں کرسکتی.پھر مِن شَرِ مَا خَلَقَ کے الفاظ سے یہ مفہوم نکلتا ہے کہ اے مخلوقات کے پیدا کرنے
والے خدا! میں تیری پناہ چاہتا ہوں پیدائش کے ان نقائص سے جو کسی چیز کے پیدا ہوتے
وقت اس میں رہ جاتے ہیں اور اس چیز کی ترقی اور کمال کے حاصل کرنے میں روک بن جاتے
ہیں.چنانچہ دنیا میں جب بھی خرابی ہو گی تین وجہ سے ہوگی.(1) پیدائش میں نقص کی وجہ
1113
Page 1122
سے.(2) انتہا خراب ہونے کی وجہ سے (3) یا زندگی کے درمیانی حالات کے خراب
ہونے کی وجہ سے.مِنْ شَرِ مَا خَلَقَ میں پیدائش میں نقص رہ جانے کی وجہ سے جو خرابی انسان کو لاحق ہوسکتی
ہے اس سے پناہ سکھائی گئی ہے.کیونکہ پیدائش میں نقص یا خرابی ہو تو تباہی آجائے گی اور مقصد
حاصل نہیں ہو سکے گا.اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے کہ کہو میری پیدائش میں
جو نقص رہ گیا ہے اس سے پناہ مانگتا ہوں.انسان جب پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ کی بداعمالیوں
اور بُرائیوں سے بھی ورثہ پاتا ہے.جس قسم کے افعال اس کے ماں باپ کرتے ہیں وہ بھی
انہیں کی طرف مائل ہو جاتا ہے.اسی لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب
میاں بیوی ملیں تو دعا مانگ لیں کہ ہم شیطان سے پناہ مانگتے ہیں اور اپنی اولاد کے لئے بھی
شیطان سے پناہ چاہتے ہیں.اس سے معلوم ہوا کہ بعض خرابیاں ورثہ میں پیدا ہو جاتی ہیں.اور
پھر ظاہری لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بچے عام طور پر ماں باپ کے قد علم ،حوصلہ اور خیالات کو
لیتے ہیں.چوری کرنے والے یا جھوٹ بولنے والے لوگوں کے بچے چوری اور جھوٹ کی طرف
راغب ہوتے ہیں.مسلول باپ کا بچہ بھی مسلول ہو جاتا ہے.پس یہ بات بالکل درست ہے کہ
ورثہ میں خرابیاں اور کمزوریاں بھی ملتی ہیں اور خوبیاں بھی ملتی ہیں....اس لئے خدا تعالیٰ نے یہ
دعا سکھائی کہ کہو اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِ مَا خَلق اے میرے پیدا کرنے والے اور میری
پرورش کرنے والے اب اگر مجھ میں ورثہ کے طور پر یا کسی اور اثر سے کوئی کمزوری اور خلقی نقص
رہ گیا ہے تو اس کے اثر سے مجھے بچا.تا میں تیری رضا حاصل کر سکوں اور تیرا قرب پا
سکوں.غرض اس حصہ آیت میں ان کمزوریوں سے پناہ مانگی گئی ہے جو انسان میں پیدائشی طور
پر آجاتی ہیں.قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ میں ہمیں اسی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ
انسان مخلوقات کا ایک جزو ہے.وہ جمادات، نباتات، حیوانات سے علیحدہ نہیں ہے.اگر ہم
1114
Page 1123
ان چیزوں سے علیحدہ ہوتے تو ہمیں یہ حکم نہ دیا جاتا کہ ہم ان چیزوں کے شر سے پناہ مانگیں.مِنْ شَرِ مَا خَلق کے الفاظ ظاہر کرتے ہیں کہ ان چیزوں کی برائی ہم تک پہنچ سکتی ہے اس لئے
ہمیں ان کے شر سے محفوظ رہنے کے لئے ہر وقت دعا کرنی چاہئے.غرض ہمیں یہ بتایا گیا کہ تمام
جمادات سے ہمیں شر بھی پہنچ سکتا ہے اور خیر بھی.تمام نباتات سے ہمیں شر بھی پہنچ سکتا ہے اور خیر
بھی.اور تمام حیوانات سے ہمیں شر بھی پہنچ سکتا ہے اور خیر بھی.اوع ہماری جڑیں ان تینوں
کروں میں دبی ہوئی ہیں.ان حالات میں ہمیں دعا سکھائی کہ اگر ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں
اپنی جماداتی ، نباتاتی اور حیوانی ہستی کا خیال رکھنا چاہئے.جب تک جڑوں کو پانی نہ دیا جائے
اس وقت تک درخت سرسبز نہیں رہ سکتا.اسی طرح انسان کی روحانیت اعلیٰ درجہ تک نہیں پہنچ
سکتی جب تک وہ جمادات، نباتات اور حیوانات میں سے طیب اشیاء کو استعمال نہیں کرتا اور ان
کے شرسے بچتا نہیں ہے.اسی طرح درخت میں بعض امراض اس کی جڑوں سے پیدا ہوتی ہیں
اور بعض پتوں سے.سورۃ فلق کی ان آیات میں ہمیں ان امراض سے بچنے کا علاج بتایا ہے جو
ہمیں جڑھ سے پہنچ سکتی ہیں.پس فرمایا تمہیں دعا کرنی چاہئے کہ وہ خدا جس نے تمام مخلوقات
پیدا کی ہے ہم اس کی پناہ میں آتے ہیں تا کہ ہمیں تمام مخلوقات کی خیر توملتی رہے لیکن ان کا شر ہم
تک نہ پہنچ سکے کیونکہ ان چیزوں کا خالق ہی اگر چاہے تو ایسا ہوسکتا ہے.وگرنہ نہیں.قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ میں ایک اور اہم امر کی طرف بھی اُمتِ مسلمہ
کے ہر فرد کی توجہ مبذول کرائی گئی ہے اور وہ یہ کہ سورۃ الفلق سے پہلی سورۃ یعنی سورۃ الاخلاص
میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو توحید کامل کا سبق دیا تھا.اس سورۃ کے بعد قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ
الْفَلَقِ مِنْ شَرِ مَا خَلَقَ کہہ کر یہ بتایا ہے کہ اے وہ شخص جو ایمان لایا ہے ہماری ذات پر
ہمارے کلام پر اور اس میں سے بھی ہمارے قرآن پر ہم اسے کہتے ہیں کہ جاؤ اور جا کر لوگوں میں
اپنے اس ایمان کا اعلان کرو اور کہو اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ تم لوگ دنیا میں بھروسہ کرتے ہو اپنے
ماں باپ پر تم لوگ بھروسہ رکھتے ہو اپنے رشتہ داروں اور دوستوں پر تم لوگ بھروسہ رکھتے ہو
1115
Page 1124
اپنے خاندانوں پر اور جتھوں پر تم لوگ بھروسہ رکھتے ہو اپنے محلہ کے لوگوں پر اور محلہ کے
چوہدریوں پر تم بھروسہ رکھتے ہو اپنی حکومتوں پر.اور تم بھروسہ رکھتے ہو اپنے ملک کی فوجوں
پر اور اپنے ملک کے استادوں پر جولوگوں کو جہالت سے بچاتے ہیں اور ملک کے ڈاکٹروں پر
جو اہل ملک کی صحت کی ترقی میں مدد دیتے ہیں اور ملک کو بیماریوں سے محفوظ رکھنے کی کوشش
کرتے ہیں.غرضیکہ تم لوگ ان چیزوں پر بھروسہ رکھتے ہو.مگر میرا ان میں سے کسی پر بھروسہ
نہیں.بلکہ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ان کی طرف سے توجہ ہٹا کر میں نے رَبُّ الْفَلَق کے ساتھ کو
لگالی ہے اور اسی پر میرا بھروسہ ہے.اللہ تعالیٰ نے اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ سے پہلے قُل کا لفظ لا کر ہر مسلمان کو گویا یہ ہدایت دی
ہے کہ جب تم اللہ تعالیٰ کی صحیح توحید کا علم حاصل کر چکے ہو تو ہر مجلس میں جا کر یہ اعلان کروتا ہر
شخص تمہارا نگران بن جائے.پس سورۃ فلق کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک مومن سے یہی کہا ہے کہ اگر تمہارے
اندر واقعی ایمان پیدا ہو چکا ہے تو ساری دنیا کو چیلنج دے دو اور سب لوگوں کے سامنے دنیا سے
بے پروا ہو کر اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کی پناہ میں دے دینے کا اعلان کر دو.اللہ تعالیٰ نے یہاں قل کا لفظ رکھ کر بتا دیا کہ اب تم سارا قرآن کریم پڑھ چکے اب
تمہارے دل کا ایمان پختگی حاصل کر چکا ہے اب اسے مخفی نہیں رکھا جا سکتا.جو بات تم ہمارے
سامنے آ کر کہتے ہو اسے یا تو کھلے میدان میں ظاہر کرو.لوگوں کو اس پر گواہ بلکہ قاضی اور حج
بناؤ.تاجب تمہارا عمل اس کے خلاف ہو تو وہ ملامت کر سکیں اور یا پھر اس دعوی کو ترک کر دو.ہم تمہارے اس دعویٰ کو نہیں مانتے جو تم علیحدگی میں ہمارے حضور کرتے ہو.اور نماز پڑھتے
وقت کہتے ہو کہ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ.اے میرے رب میں تیری پناہ میں آتا ہوں.تمہارے اس
دعویٰ کے معنے تو یہ ہیں کہ تمام مخلوق سے تمہارا رشتہ ٹوٹ چکا اور خدا تعالیٰ کے ساتھ قائم ہو گیا.اب تمہارا بھروسہ ماں باپ، بھائی بہن، دوست احباب، رشتہ داروں ، قوم وحکومت پر نہ ہو
1116
Page 1125
گا.ان سب کے تعلق ٹوٹ کر اب خدا تعالیٰ کے ساتھ قائم ہو گیا.اور یہ ایک ایسا دعویٰ ہے
جس کی حقیقت تم پر اس وقت تک واضح نہیں ہو سکتی جب تک کہ تم لوگوں کو اس پر گواہ نہ بنالو
اور جو انسان اس مقام پر کھڑا ہو وہ کس طرح اطمینان کا سانس لے سکتا ہے جب تک وہ اپنے
عمل سے اس دعویٰ کی تصدیق نہ کر دے.م مومن خدا تعالیٰ پر توکل کرنے والا ہوتا ہے.اور جب وہ لوگوں کے سامنے کہتا ہے کہ
اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ.میں رَبُّ الفَلَق کی پناہ میں آتا ہوں تو پھر وہ بندوں کی طرف نگاہ نہیں کر سکتا
بلکہ خدا تعالیٰ پر ہی یقین رکھتا ہے.تیسرے معنے فلقی کے جہنم کے ہیں.ان معنوں کے اعتبار سے قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ
الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ کا مفہوم یہ ہوگا کہ میں جہنم کے پیدا کرنے والے رب کی پناہ میں آتا
ہوں.اور ان شدائد سے بھی جو اس جہنم میں پیدا کئے گئے ہیں.قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ میں یہ بتایا گیا ہے کہ اے مسلمانو! تم کو دعا
کرنی چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کر کے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
مبعوث کر کے تمہیں انفرادی اور اجتماعی طور پر جنت میں داخل کر دیا ہے.كُنْتُمْ عَلى شَفَا
حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا - تم آگ کے کنارے پر تھے تم کو نکال کر جنت میں داخل
کر دیا.اللہ نے تمہیں ذہنی اور قلبی سکون عطا کیا.تم ایک ہاتھ پر جمع ہو گئے تم میں ایک
دوسرے کے ساتھ محبت کا وہ اعلیٰ مقام پیدا ہو گیا کہ تمہارے لئے یہ دنیا جنت بن گئی.تم کو
خدا تعالیٰ میں گیا اور تمہارے دلوں کو اطمینان حاصل ہو گیا.پس ان نعمتوں کو یا درکھو اور جہنم
کے رب کی پناہ میں آؤ اور اس کے شدائد سے بچنے کے لئے بھی اس کی پناہ چاہوتا کہ جہنم کبھی
تمہارے قریب نہ آئے.یعنی ایسی حالت پیدا نہ ہو کہ تمہارا انفرادی اور قومی اطمینان ختم ہو
جائے.تمہارے اندر لڑائی جھگڑے پیدا ہو جائیں.تم قرآن کریم کی تعلیم کو چھوڑ دو اور یہ دنیا بھی
تمہارے لئے جہنم بن جائے اور آخرت میں بھی جہنم دیکھنا پڑے.1117
Page 1126
چوتھے معنے الفلق کے دو پہاڑیوں کے درمیان کے میدان کے ہوتے ہیں.بعض
اقوام ایسی ہیں جو افراط کی طرف چلی گئی ہیں اور بعض تفریط کی طرف لیکن اللہ تعالیٰ کے حصول
اور دنیا میں امن و امان کا اصل طریق میانہ روی ہے.اسی لئے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اُمتِ
وسط قرار دیا ہے کہ ان
کی تعلیم میں نہ افراط پایا جاتا ہے اور نہ تفریط.اور جو ایسی تعلیم ہو وہ اعلیٰ
درجہ کی ہوگی اور اس سے دنیا میں امن پیدا ہو گا.تو فرما یا قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِ مَا
خلق.کہ اے مسلمانو! کہو ہم اس رب کی پناہ چاہتے ہیں جس نے افراط اور تفریط کی دو
پہاڑیوں کے درمیان اسلام جیسا خوبصورت میدان بنایا ہے.جہاں دنیا کو چین اور آرام
حاصل ہوسکتا ہے.گویا ان آیات میں بتایا ہے کہ تم اس خدا کی پناہ چاہو جس نے اسلام جیسے
بہترین مذہب کو بھیجا، جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کامل انسان بھیجا اور جس کے
ذریعہ سے تم کو قرآن جیسی کامل تعلیم ملی.تم اس بات سے پناہ چاہو کہ تمہارے لئے کوئی شر پیدا
نہ ہو جائے.یعنی ایسا نہ ہو کہ کسی وقت کوئی ایسا شر پیدا ہوجس کی وجہ سے تم اللہ تعالیٰ کی بہترین
تعلیم سے علیحدہ ہو جاؤ.اسلام کو چھوڑ دو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے کنارہ کشی کرلو
جس کا نتیجہ یہ ہو کہ تم مشکلات میں مبتلا ہوجاؤ اور تمہاری زندگی تمہارے لئے مشکل ہو جائے.ا اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ کہ کر اس طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے اور اس
کی ربوبیت سے فیض پانے کا صحیح طریق میانہ روی ہے.نہ انسان افراط کو اختیار کر کے
اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتا ہے اور نہ تفریط والے راستے کو اختیار کر کے.ہاں اگر میانہ روی کو
اختیار کرتا ہے تو خدا تعالیٰ تک پہنچ سکتا ہے لیکن اس تک پہنچنے میں بہت سی روکیں
ہیں....اس لئے کامیابی کا حقیقی خواہاں وہی ہوتا ہے جو خدا تعالیٰ کے حضور گرتا ہے اور کہتا
ہے اعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَق - اے خدا مجھے معلوم نہیں کہ میرے راستہ میں ہلاکت
اور رکاوٹیں کہاں کہاں سے آرہی ہیں.اس لئے اسے خدا جو خالق ہے تمام چیزوں کا ان کے شر
سے مجھے بچا.کیونکہ ان کے شر کا تجھے ہی پتہ ہے.پس یہ ترقی کا پہلا زینہ ہوتا ہے کہ انسان ہر
1118
Page 1127
ذرہ سے حتی کہ اپنے نفس سے بھی ڈرتا ہے اور اس کے شر سے پناہ مانگتا ہے.پھر یہی نہیں کہ
مومن اپنے ایمان کے متعلق ڈرتا ہے کہ ایسا نہ ہو میرے دل میں تکبر پیدا ہو جائے اور میں مارا
جاؤں بلکہ وہ قرب الی اللہ سے بھی ڈرتا ہے کیونکہ یہ بھی ہلاکت کا موجب بن جاتا ہے جیسے کہ
بلغم کے لئے ہو گیا تھا....پس مِن شَرِّ مَا خَلَقَ سے بتایا کہ انسان کو ہر ذرہ سے ڈرنا چاہئے
اور چونکہ انسان کو علم نہیں ہوتا کہ کونسی چیز اس کی ہلاکت کا باعث ہوسکتی ہے اس لئے ان اشیاء
کے پیدا کرنے والے خدا سے ہی پناہ مانگنی چاہئے.الفلق کے پانچویں معنے اس لکڑی کے ہیں جس میں مجرموں کو قطار میں کھڑا کیا جاتا
ہے.پس ان معنوں کے اعتبار سے اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِ مَا خَلق کے یہ معنے ہوں گے
کہ میں قید خانوں کے مالک کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ ایسا نہ ہو کہ میں قید خانے میں
پڑ جاؤں اور اس کی شدائد اور مشکلات مجھے برداشت کرنی پڑیں.گویا اس میں قومی لحاظ سے
بھی دعا سکھائی گئی ہے اور فردی لحاظ سے بھی.یعنی ایسا نہ ہو کہ ہماری قوم آپس میں لڑ پڑے.اور ایک دوسرے کو قید خانوں میں ڈال کر شدائد میں مبتلا کر دے.یا ایسا نہ ہو کہ کوئی مخالف
حکومت اٹھے اور اسلامی حکومت کو برباد کر دے اور مسلمانوں کو قید و بند کی مشکلات سے دو چار
ہونا پڑے اور مسلمانوں کا آرام ختم ہو جائے.اسی طرح فردی لحاظ سے یہ دعا سکھائی کہ تمہیں دعا
کرنی چاہئے کہ تم دانستہ یا نا دانستہ کوئی ایسی بات نہ کر بیٹھو جس سے تمہیں قید و بند کی مشکلات
سے دوچار ہونا پڑے.الفلق کے چھٹے معنے اُس دودھ کے ہیں جو دودھ پینے کے بعد پیالے کے آخر میں
تھوڑ اسا بچ جاتا ہے.ان معنے کے اعتبار سے قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ کا یہ
مفہوم ہوگا کہ اے خدا تو نے مجھے وہ کامل تعلیم قرآن کریم کے ذریعہ سے دی ہے جو اس پیالہ کی
مانند ہے جو دودھ سے بھرا ہوا ہو.ایسا نہ ہو کہ کسی وقت میری کمزوریوں کی وجہ سے میرے
پاس اس تعلیم میں سے تھوڑا سا حصہ رہ جائے اور روحانی طور پر امیر ہونے کے بعد میں غریب
1119
Page 1128
ہو جاؤں....دودھ سے مراد قرآنی تعلیم ہے جو فطرتِ صحیحہ کے مطابق ہے.پس قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ میں بتایا کہ مسلمانوں کو دعا کرنی چاہئے کہ اللہ
تعالیٰ ان کو قرآنی تعلیم پر پوری طرح عمل کرنے کی توفیق دے اور وہ اس تعلیم کی حفاظت
کرتے رہیں.اور ایسا نہ ہو کہ کسی وقت اس پر عمل کو چھوڑ کر اس شخص کی طرح ہو جائیں جس
کے پاس تھوڑا سا دودھ رہ جاتا ہے.دنیا میں جب کوئی شخص امیر ہونے کے بعد پھر غریب
ہوتا ہے تو اُسے بہت تکلیف ہوتی ہے اور اس کی زندگی اس کے لئے دوبھر ہو جاتی ہے.پس
انفرادی لحاظ سے بھی اس میں یہ دعا سکھائی گئی ہے کہ ایسانہ ہو وہ نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو
دی ہیں اور جن کے ذریعہ سے وہ آرام و اطمینان کی زندگی بسر کر رہا ہے وہ ہمتیں ہاتھ سے جاتی
رہیں اور اس کی زندگی کے دن مشکل سے کٹیں.پھر اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ ایسا نہ ہو اسلام کے غلبہ کی وجہ سے جو مسلمانوں کو رفاہیت حاصل
ہے وہ کسی وقت مسلمانوں کی حکومت کے ٹوٹ جانے کی وجہ سے تکلیف میں بدل جائے اور مسلمان
کڑھتے رہیں.بلکہ اگر کوئی ایسا وقت آئے تو اللہ تعالیٰ خود دستگیری کرے اور پھر سے سامان پیدا کر
دے کہ مسلمانوں کی کمزوری طاقت سے اور ضعف کے دن شوکت سے بدل جائیں.ساتویں معنے الفلق کے الْأَنْهَارُ کے بھی ہیں.اور ربُّ الفلق کے معنے ہوں گے
دریاؤں کا رب.اس لحاظ سے قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ میں یہ دعا سکھائی گئی
ہے کہ کہو میں انہار یعنی دریاؤں کے پیدا کرنے والے رب کی پناہ میں آتا ہوں اس بات سے
کہ ان کے ذریعہ سے مجھے یا میری قوم کو کوئی شر نہ پہنچ جائے.یہ ظاہر ہے کہ دریاؤں کے ذریعہ سے ملک سیراب ہوتے ہیں اور ان پر ملکوں کی خوراک کا
انحصار ہوتا ہے.اگر صحیح رنگ میں ان سے پانی ملتار ہے، دریاؤں سے نہریں نکالی جائیں اور
ان نہروں سے زمینوں کو سیراب کیا جائے تو وہ ملک کے لئے مفید ہوتے ہیں.لیکن اگر
دریاؤں میں طغیانی آجائے تو نہ صرف یہ کہ فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں بلکہ لوگ بھی ڈوب کر مر جاتے
1120
Page 1129
ہیں.پس دریا ایک مفید چیز ہے جس پر زندگی کا دارومدار ہے.لیکن جب اس کا مضر پہلو ظاہر
ہوتا ہے تو وہ زندگی بخش ہونے کی بجائے زندگی ختم کرنے کا ذریعہ ہو جاتا ہے.درحقیقت ہر
چیز کا یہی حال ہے.اس کا فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے.تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ مسلمانوں
کو دعا کرتے رہنا چاہئے کہ جو کچھ جسمانی اور روحانی لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ ان کے
لئے فائدہ بخش ہو اور اس کے مضرات سے اللہ تعالیٰ خود ہی بچاتا رہے.وَمِن شَرِ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ
لفظ غایت اور وقت کے مختلف لغوی معانی پیش نظر رکھتے ہوۓ وَ مِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا
وقت کے معنے ہوں گے
(1) میں پناہ چاہتا ہوں رات کی تاریکی کے شہر سے جب کہ اندھیرا چھا جائے.(2) میں پناہ چاہتا ہوں اس وقت کے شر سے جب سورج غروب ہو جائے.(3) میں پناہ چاہتا ہوں اس وقت کے شر سے جب چاند اور سورج کو گرہن لگے.(4) میں پناہ چاہتا ہوں اس وقت کے شر سے جب کہ فراخی کے بعد تنگی ہو جائے.(5) میں ان حوادث سے پناہ چاہتا ہوں جو رات کے وقت آئیں.(6) میں اُس وقت کے شر سے پناہ چاہتا ہوں جب کہ انسان گڑھے میں دخل ہو جائے.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنْ شَرِ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ یعنی میں فاسق کے شر سے پناہ مانگتا
ہوں جب کہ وہ وَ قُوب اختیار کر لیتا ہے...غاسق کے معنے رات کے ہیں اور وقت کے معنے
اندھیرے اور ظلمت کے چھا جانے کے ہیں.اسی طرح غاسق کے معنے سورج کے ہیں اور
وقت کے معنے غائب ہونے کے ہیں.پس ان معنوں کے اعتبار سے وَ مِنْ شَرِ غَاسِقٍ إِذَا
وَقَبَ کا مفہوم یہ بنے گا کہ میں اُس وقت کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جبکہ سورج غروب ہو
جائے اور سخت تاریکی چھا جائے.قرآن کریم میں سورۃ الاحزاب میں...رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چمکنے والا سورج قرار دیا
1121
Page 1130
گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور دنیا کو منور کرے گا.پس سورۃ
الخلق میں قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِ مَا خَلَق کے الفاظ کہہ کر یہ اشارہ فرمایا کہ اے
محمد رسول
اللہ! یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے کہ آپ کی لائی ہوئی تعلیم ساری دنیا میں پھیل جائے اور
آپ وسط آسمان میں سورج کی طرح چمک کر ساری دنیا کو منور کر دیں.پھر اس کے بعد ومن
شَرِ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ کہہ کر یہ ہدایت کی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے التجا کرنی چاہئے کہ اس کے
بعد کوئی ایسا وقت نہ آجائے کہ آپ کا روشن چہرہ دنیا کی آنکھوں سے اوجھل ہو جائے اور لوگ
آپ
کی روشنی سے محروم ہو جائیں اور دنیا پر تاریکی چھا جائے.اسی طرح اُمتِ مسلمہ کے ہر فرد
کو حکم دیا کہ وہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ جو کمال انہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
ذریعہ سے دینے والا ہے اور جو روحانی اور جسمانی ترقیات مسلمانوں کو دی جانے والی ہیں ان
کے بعد ان پر زوال نہ آجائے اور ایسا نہ ہو کہ وہ کسی وقت قرآنی تعلیم پر عمل کرنا چھوڑ دیں اور
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی اور قرآن کریم کے نور سے محروم ہوجائیں اور ان پر تاریکی
چھا جائے.اور اسی طرح مادی ترقیات ملنے کے بعد کوئی ایسا سبب پیدا نہ ہو جس سے وہ تباہی
کے گڑھوں میں جاگریں اور اگر کوئی ایسی بات مسلمانوں کی غلطیوں کی وجہ سے پیدا ہو جائے تو
پھر اللہ تعالیٰ ان کی خود دستگیری فرمائے اور ایسے حالات پیدا کر دے کہ پھر سے محمد رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم کا روشن چہرہ دنیا دیکھنے لگے اور تنزل کے دن ترقی سے بدل جائیں.عشقی کے ایک معنے کسی چیز کی کثرت کے ہیں.چنانچہ کہتے ہیں غَسَقَتِ السَّمَاءُ
غَسْقًا أَى انْصَبَّتْ وَ اَرشت کہ باولوں میں اتنا پانی تھا کہ وہ زور سے بہ پڑے.اور اسی
طرح آنکھ جب آنسوؤں سے ڈبڈبا آئے اور خود بخود آنسو بہنے لگیں تو اس وقت بھی غسق کا لفظ
استعمال کیا جاتا ہے.پس ان معنے کے اعتبار سے وَمِنْ شَرِ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ کے معنے ہوں
گے کہ آسودگی کے بعد تنگی سے میں پناہ چاہتا ہوں.یہ ظاہر ہے کہ کبھی دولت کی زیادتی خراب
کرتی ہے اور کبھی دولت کی کمی.جیسے کبھی نور کی زیادتی کی وجہ سے آنکھیں ماری جاتی ہیں اور
1122
Page 1131
کبھی تاریکی کی وجہ سے آنکھیں ضائع ہو جاتی ہیں.سورج کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے والا بھی
اپنی آنکھیں کھو بیٹھتا ہے اور اندھیرے میں رہنے والوں کی بھی آنکھیں ماری جاتی ہیں.جب
تک درمیانی راہ اختیار نہ کی جائے چین و آرام حاصل نہیں ہوسکتا.پس من شر ما خلق میں تو مال کی زیادتی اور اس کے نقصان سے بچنے کے لئے دعا سکھائی
اور وَمِن شَرِ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ میں مال کی کمی کے نقصانات سے محفوظ رہنے کی طرف اشارہ
کیا.کیونکہ یہ حالت بھی اتنی خراب ہوتی ہے کہ اس کے متعلق کہا گیا ہے کہ حادَ الْفَقْرُ آن
يكُونَ كُفْرًا یعنی مال کی کمی بعض اوقات انسان کے ایمان کو ضائع کر دیتی ہے.پس
اللہ تعالیٰ نے ایسی حالت سے محفوظ رہنے کے لئے یہ دعا سکھائی کہ تم اللہ تعالیٰ سے التجا کرو کہ
مال ملنے کے بعد پھر فقر کی نوبت نہ آئے.غاسق کے معنے سورج کے بھی ہیں اور چاند کے بھی.اور وقُوب کے معنے گرہن لگنے
کے بھی ہیں.پس وَ مِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ کے معنے ہوں گے میں اس وقت کے شر سے پناہ
چاہتا ہوں جبکہ سورج اور چاند کو گرہن لگے.سورج اور چاند کو گرہن لگنے کے دو معنے ہیں:
الف: یعنی وہ انوار جو خدا تعالیٰ کی طرف سے انسان کی ترقیات کے لئے ضروری ہیں، مٹ
جائیں اور جو چیز میں اس نور کو مکتسب کرتی ہیں وہ بھی اس نور کو حاصل نہ کرسکیں.جیسے سورج
کی ذاتی روشنی ہے اور چاند اس سے روشنی حاصل کر کے دنیا کو منور کرتا ہے.اگر ایسے حالات
پیدا ہوجائیں کہ چاند سورج سے روشنی حاصل نہ کر سکے اور تاریک ہو جائے تو یہ حالت بھی و مِین
غيز نماي اذا وقت کے ماتحت آئے گی.پس وَ مِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ میں گود عا سکھائی گئی ہے.لیکن اس میں یہ پیشگوئی ہے کہ
ایک زمانہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور بھی لوگوں کی نگاہوں سے مخفی ہو جائے گا.اور نہ
صرف یہ کہ آپ کا نور عوام الناس نہیں دیکھ سکیں گے بلکہ آپ کے نور کو اپنے اندر جذب کر کے
1123
Page 1132
اُسے دنیا میں پھیلانے والے صلحاء اور اولیاء جو قمر کا درجہ رکھتے ہیں وہ بھی موجود نہیں ہوں گے
اور تاریکی ہی تاریکی چھا جائے گی.پس ایسے وقت میں جو شر امت مسلمہ کو پہنچ سکتا ہے اس
سے بچنے کے لئے پناہ طلب کرنے کی ہدایت کی گئی ہے.باء: ظاہری لحاظ سے یہ بھی مراد ہوسکتی ہے کہ اس آیت میں سورج اور چاند کو گرہن لگنے کی
طرف اشارہ ہے اور بتایا ہے کہ جب ایسا زمانہ آئے تو اس کے شرور سے پناہ چاہو.احادیث میں یہ بات پوری وضاحت سے بیان ہوئی ہے کہ امت محمدیہ پر روحانی اور جسمانی
ترقیات کے بعد ایک ایسا زمانہ بھی آنے والا ہے جب کہ وہ تنزل کے گڑھے میں گر جائے گی
اور اسلام کا صرف نام ان میں باقی رہ جائے گا.اور قرآن کریم صرف اوراق میں ہو گا لیکن اس پر
عمل نہیں کیا جائے گا.ہر قسم کی خرابی ان میں پھیل جائے گی اور ان کی وہ حکومتیں اور شان و
شوکت جو قرآن کی بدولت ان کو ملی تھیں ختم ہو جائیں گی.ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ امت محمدیہ
کی دستگیری فرمائے گا اور ایک ایسے شخص کو مبعوث کرے گا جو سیح اور مہدی کا نام پائے گا.اور
اس کے ذریعہ اسلام ہر حیثیت سے غالب ہو جائے گا اور اس کی مٹی ہوئی عظمت پھر سے قائم ہو
جائے گی.مہدی اور مسیح کے مبعوث ہونے کے وقت کئی نشانات ظاہر ہوں گے اور ان میں
سے ایک نشان سورج اور چاند کو رمضان کے مہینے میں گرہن لگنے کا بھی ہے....پس مِن شَرِ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ میں اس بات کے لئے دعا سکھائی گئی ہے کہ جب ایسا زمانہ آئے
کہ اسلام کمزوری کی حالت میں ہو اور اللہ تعالیٰ مہدی اور مسیح کو دین اسلام کی عظمت قائم کرنے کے
لئے کھڑا کرے تو اس زمانہ کے شرور سے اللہ تعالیٰ بچائے اور اس کے اعوان و مدد گاروں سے
بنائے اور اس کے مخالف لوگوں پر جو عذاب آئیں گے، اللہ تعالیٰ ان سے محفوظ رکھے.مِنْ شَرِ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ میں انجام کی خرابی سے بچنے کے لئے دعا سکھائی کیونکہ کبھی
ابتدا تو اچھی ہوتی ہے لیکن انتہا خراب ہو جاتی ہے.بعض اوقات ایسی بے موقعہ اور بے محل
انتہا ہوتی ہے کہ بجائے اس کے کہ نیکی قائم رہے بربادی ہو جاتی ہے.اسی وجہ سے اس آیت
1124
Page 1133
میں انسانی زندگی کی درمیانی حالت کو چھوڑ کر انتہا کو لے لیا.یعنی من شر ما خلق میں ابتدا کولیا
اور اس کے بعد درمیانی حالت کو بیان نہیں فرمایا بلکہ انتہا کو لے لیا اور فرمایا وَ مِنْ شَيْرِ غَاسِقٍ
إِذَا وَقَبَ کہ وہ ڈوبنے والی اور آنکھوں سے اوجھل ہونے والی چیز جو گڑھے میں چلی جاتی ہے
یعنی جبکہ انسان مر جاتا ہے زمین میں دفن ہو جاتا ہے اُس وقت کے بدنتائج سے بھی پناہ مانگتا
ہوں جس طرح پیدائشی کمزوریوں سے جو میرے لئے روک ہوسکتی تھیں پناہ مانگتا ہوں.اسی
طرح اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ ایسی حالت نہ پیدا ہو جائے کہ میرے مرنے سے ایسے
نقائص پیدا ہو جائیں جن سے دین کو نقصان پہنچے یا میرے کام ادھورے رہ جائیں اور ان کا انجام
اچھا ہونے کی بجائے بُرا ہو جائے...وَمِن شَرِ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ میں جامع دعا سکھائی گئی
ہے اور بتایا گیا ہے کہ امت مسلمہ کے ہر فرد کو یہ دعا کرنی چاہئے کہ اللہ تعالیٰ چین و آرام کے
بعد جھگڑوں میں پڑنے اور حکومت کے بعد ماتحتی کی ذلت سے بچائے اور ایسے حالات سے
محفوظ رکھے جن کی وجہ سے تاریکی ہی تاریکی نظر آتی ہے.وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ میں یہ مضمون بھی بیان ہوا ہے کہ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ
کے حکم کے مطابق جب کامل تو حید کو مانے والا یہ اعلان کرتا ہے کہ مجھے کسی کی پرواہ نہیں تو
اس وقت مخالفت شروع ہو جاتی ہے.اور دوست دوستیاں چھوڑ دیتے ہیں اور ہمدرد بھی مخالف
ہو جاتے ہیں گویا ایک قسم کی ظلمت چھا جاتی ہے اور اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے.فرمایا:
ایسے وقت میں میں اللہ تعالیٰ کی ہی پناہ چاہتا ہوں.وَمِنْ شَرِّ التَّقْقت فِي الْعُقَدِ
النفقت اور العُقد کے مختلف لغوی معنوں کے پیش نظر وَ مِنْ شَيْرِ النَّقْفتِ فِي الْعُقَدِ
کے معنے ہوں گے :
(1) میں پناہ چاہتا ہوں ان نفوس کے شر سے جو دوستیوں اور معاہدات کو نڑ وادیں.(2) میں پناہ چاہتا ہوں ان گروہوں کے شر سے جو خلفاء کا مقابلہ کروائیں اور ان کی بیعت
1125
Page 1134
تڑوادیں.(3) میں پناہ چاہتا ہوں اُن نفوس کے شر سے جو اتحاد کو برباد کرائیں اور مسلمانوں کی
حکومتوں کو تباہ کرائیں.العقد کے معنے ہیں الْوَلَايَةُ عَلَى الْبَلَدِ یعنی حکومت یا گورنری.اور اسی طرح سے اس
کے معنے الْبَيْعَةُ لِلْمُلَاةِ کے بھی ہیں.یعنی حُكّام اور خلفاء کی بیعت.اور نَفْتُ فِي الْعُقَدِ
ایک محاورہ ہے جس کے معنے تعلقات قطع کروانے کے ہیں...-
پس وَ مِنْ شَيْرِ التَّفتِ فِي الْعُقَدِ میں یہ دعا سکھائی گئی ہے کہ مسلمانوں کو ایسے لوگوں سے
اللہ تعالیٰ کی حفاظت طلب کرنی چاہئے جو تعلقات بیعت کو تڑ وادیں اور مسلمانوں کے اتحاد میں
رخنہ پیدا کردیں.نفت کے معنے لکھنے کے بھی ہیں.اس لحاظ سے النفقت کے ایک معنے لکھنے والے
نفوس یا گروہوں کے بھی ہوں گے.گویا ان معنوں کے اعتبار سے مِنْ شَيْرِ التَّقْفَتِ فِي الْعُقَدِ
میں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ آخری زمانہ میں بڑی کثرت سے ایسالر یچر شائع کیا جائے گا
جو خدا اور اس کے رسول کے خلاف ہو گا اور جس کی وجہ سے دنیا میں بڑا بھاری شر اور فتنہ پیدا ہو
جائے گا.اس فتنہ سے بچنے کے لئے یہ دعا سکھائی گئی ہے کہ وہ آخری زمانہ جس میں بڑی
کثرت سے خدا تعالیٰ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لٹریچر شائع کیا جائے گا اللہ
تعالیٰ اس کے شر سے ہمیں بچائے اور ہمیں اپنی حفاظت اور پناہ میں رکھے.ضمنی طور پر اس سے یہ مراد بھی ہو سکتی ہے کہ آخری زمانہ میں ایسا لٹریچر شائع کیا جائے گا
جس میں حکومت اور رعایا کے تعلقات کو بگاڑنے کی کوشش کی جائے گی.وَ مِنْ غَيْرِ التَّقْفتِ فِي الْعُقَدِ میں زندگی کے درمیانی عرصہ میں جو خرابیاں پیش آجایا
کرتی ہیں، ان سے پناہ طلب کرنے کی ہدایت کی گئی ہے.اور بتایا گیا ہے کہ بعض اوقات
1126
Page 1135
پیدائش میں بھی کوئی نقص اور کمزوری نہیں ہوتی اور بے موقع موت بھی نہیں ہوتی.ہاں درمیانی
زندگی کے ساتھ تعلق رکھنے والی بعض کمزوریاں ہوتی ہیں اور ان کے بھی دو حصے ہوتے ہیں
(1) وہ حصہ جو پیدائش کے زمانہ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے (2) وہ حصہ جوموت کے زمانہ کے
ساتھ تعلق رکھتا ہے.پہلے حصہ کے متعلق فرمایا وَ مِنْ شَرِ النَّفْتِ فِي الْعُقَدِ یعنی انسان کی
ابتدائی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ ماں سے ایسے ہی خوراک لیتا ہے جیسے پورا جڑ سے لیتا ہے.گو یار بوبیت کے لحاظ سے اس کا ماں باپ سے ظاہری تعلق ہوتا ہے.اور باطنی لحاظ سے خدا
تعالیٰ سے تعلق ہوتا ہے.یعنی وہ روحانی طور پر خدا تعالیٰ کا فرزند ہوتا ہے کیونکہ خدا تعالیٰ ہی
اسے پیدا کر تا خدا تعالیٰ ہی اس کی ربوبیت کرتا اور اُسے بڑھاتا ہے.آیت زیر تفسیر میں بھی اسی
مضمون کی طرف اشارہ فرمایا کہ خدا تعالیٰ سے انسان کا تعلق اور معتقد ایسا ہے کہ تمام قو تیں اسی
سے حاصل ہوتی ہیں اور نشو نما پاتی ہیں.مگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض شریر لوگ خیالات میں
وسوسے ڈال کر بندہ کو خدا تعالیٰ سے علیحدہ کر وا دیتے ہیں اور نالائق بندہ خدا تعالیٰ کو چھوڑ دیتا
ہے.جس طرح دنیا میں نالائق بچے ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں اور ان سے قطع تعلق کر لیتے
ہیں.اس لئے خدا تعالیٰ نے دعا سکھلائی کہ کہو ایسا نہ ہو کہ وہ گرہ جس سے ہم خدا تعالیٰ سے
فیوض حاصل کرتے ہیں وہ ٹوٹ جائے بلکہ ایسا ہو کہ میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق روحانی رب
ہونے کے لحاظ سے ہے وہ گرہ مضبوط رہے.تا ایسا نہ ہو کہ جو غذا مجھے وہاں سے ملتی ہے وہ بند ہو
جائے اور میں بلاک ہو جاؤں.الغرض مِن شَرِّ مَا خَلَقَ میں خلقی کمزوریوں سے بچنے کی دعا سکھائی.اور مِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا
وَقَبَ میں موت کے ساتھ تعلق رکھنے والی خرابیوں اور مِن شَرِ النَّفْتِ فِي الْعُقَدِ میں زندگی
میں پیش آنے والی ان باتوں سے جن سے دُور ہو کر انسان کمال سے محروم ہو جاتا ہے اور کمال
حاصل کرنے کی طاقتیں کمزور پڑ جاتی ہیں.1127
Page 1136
* وَمِنْ شَرِ التَّقْفَتِ فِي الْعُقَدِ میں یہ بتایا گیا ہے کہ کامل توحید کو ماننے والا جب یہ
اعلان کرے گا کہ اب میں نے خدا سے تعلق قائم کر لیا ہے تو کچھ دوست قائم رہیں گے اور کہیں
گے تم نے بڑا اچھا کام کیا جو اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کر لیا.مگر کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو ان
حمائت کرنے والوں کو بدظن کرنے کی کوشش کریں گے اور چاہیں گے کہ دوست بھی دشمن
بن جائیں.پس ایسے وقت کے لئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے توحید کو ماننے والے تم یہ
اعلان کر دینا کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں اُن لوگوں کے شر سے جو میرے دوستوں کے
دلوں میں وساوس پیدا کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ تعلقات محبت توڑ کر میرے دشمن ہو جائیں
اور میرے راستہ میں مشکلات پیدا کریں.فرمایا وَ مِنْ شَرِ التَّقْفتِ فِي الْعُقَدِ ایسے وقت میں جب انسان مشکلات و مصائب
میں مبتلا ہو کچھ لوگ ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں جو گرے ہوئے کو گراتے اور اسے اور زیادہ
ذلیل اور رسوا کرنے کے درپے ہو جاتے ہیں.اور جس وقت انسان مشکلات میں مبتلا ہو اس
وقت بعض لوگ اس کے رہے سہے تعلقات بھی بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسے
لوگوں کی نگاہوں میں ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں.چنانچہ یہ عام طور پر مشاہدہ میں آتا
رہتا ہے کہ گھر میں ذرا کسی بچہ پر ناراض ہوں تو دوسرے بچے جھٹ اس کے متعلق شکایتیں
کرنے لگ جاتے ہیں.کوئی کہتا ہے اتاں جان اس نے فلاں موقع پر یہ شرارت کی تھی.کوئی کہتا ہے.ابا جان اس نے یہ بھی شرارت کی تھی.غرض جب کوئی گر جائے اور ذلیل ہو
جائے تو جھٹ اس کی اور لوگ شکایتیں کرنے والے کھڑے ہو جاتے ہیں.پس ایسے حالات
میں اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی ہے کہ وہ لوگ جو تعلقات میں رخنہ ڈلوانے کی کوشش کرتے
ہیں اُن سے اللہ تعالی کی پناہ چاہو کیونکہ اللہ تعالی کا ہی فضل ہو تو انسان کے تعلقات اللہ تعالیٰ اور
اس کے نیک بندوں اور رشتہ داروں اور حکمرانوں سے قائم رہ سکتے ہیں.کیونکہ انسان کو کچھ علم
نہیں کہ کس طرف سے وسوسہ اندازی ہو کر یہ تعلقات ختم ہو جائیں اور ان میں رخنہ پڑ جائے.1128
Page 1137
وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ
وَمِن شَرِ التَّقْفتِ فِي الْعُقَدِ میں تنزل کے اسباب میں سے ایک سبب کا ذکر کیا گیا
تھا اور بتایا گیا تھا کہ اگر قومی شیرازہ بکھر جائے اور لا مرکزیت آجائے تو قوم تباہ ہو جاتی ہے.اس لئے مسلمانوں کو چاہئے کہ وہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ ایسے حالات سے بچائے اور اگر ایسے
حالات کبھی پیدا ہوں تو ان کے بدنتائج سے محفوظ رکھے.اس مضمون کے بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے قومی تباہی کا ایک اور سبب بیان فرمایا
ہے اور بتایا ہے کہ بعض اوقات کوئی قوم اس وجہ سے تباہ ہو جاتی ہے کہ کوئی بیرونی دشمن اُٹھ
کھڑا ہوتا ہے اور چاہتا ہے کہ جو نعمتیں، مال کی فراوانی اور آرام و آسائش اس قوم کو حاصل ہوتی
ہیں وہ اس سے چھین لے اور خود ان سے فائدہ اٹھائے.اگر ایسا دشمن ملک پر حملہ کرنے کے
بعد غالب آجائے تو پھر ماتحت ملک کی ترقی ختم ہو جاتی ہے اور اس کی جنت جہنم سے تبدیل ہو
جاتی ہے اور اسے مختلف قسم کے مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے.پس وَ مِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ کے الفاظ کہہ کر دعا سکھائی کہ اے مسلمانو! اللہ تعالیٰ نے
جو تمہیں غلبہ دینا ہے اور جس کے نتیجہ میں تمہاری ترقی کا سورج وسط آسمان میں چمکے گا اور تمہارا
ملک جنت بن جائے گا تم اس غلبہ کے متعلق دعا کرو کہ کوئی حاسد حملہ کر کے اس نعمت کو تم سے
چھین نہ لے.الغرض اس سورۃ میں نہایت لطیف رنگ میں مسلمانوں کے غلبہ کی بشارت دی.اور پھر
مسلمانوں کو ہدایت کی کہ وہ تنزل اور اس کے اسباب کو مدنظر رکھیں اور دعا کرتے رہیں کہ
اللہ تعالیٰ انہیں اپنی حفاظت میں رکھے.اس مضمون کو ادا کرتے ہوئے مسلمانوں پر جس جس
رنگ میں تباہی آئی تھی اس کا بھی ذکر کر دیا تا کہ مسلمان وقت پر متنبہ ہوسکیں.سورۃ الفلق میں یہ مضمون بھی بیان ہورہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کامل توحید پر ایمان لانے
والے کو صرف خدا تعالیٰ پر توکل کرنا چاہئے اور اس کی توحید کا ڈنکا ہر جگہ بجانا چاہئے.اور اگر اس
1129
Page 1138
وجہ سے مخالفت کا طوفان اُٹھے یا ایسے لوگ اُٹھ کھڑے ہوں جو عزیزوں ، دوستوں، رشتہ داروں
اور بیوی بچوں کو اُکسا کر خلاف کر دیں تب بھی اُسے کسی کی پروا نہیں کرنی چاہئے.اس مضمون
کے بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ کہ جب انسان اس
مقام پر پہنچ جائے کہ وہ کسی کی پرواہ نہ کرے تو اس کے یہ معنے ہوں گے کہ وہ حقیقت خدا تعالیٰ کا
ہو گیا اور وہ اپنے دعویٰ تو کل میں سچا تھا.اور جب وہ اس مقام پر پہنچ جائے گا تو اس کی اس ترقی
کو دیکھ کر اس کے حاسد بھی پیدا ہو جائیں گے جو طرح طرح کے طعنے دیں گے.کوئی کہے گا
کہ اتفاقا ترقی کر گیا.کوئی کچھ کہے گا اور کوئی کچھ.ایسے وقت کے متعلق اللہ تعالی نے یہ
ہدایت دی کہ اعلان کر دو کہ مجھے اس وقت ایسے حاسدوں کی بھی کوئی پروا نہیں.میں اس وقت
بھی اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اور اسی کی پناہ میں آتا ہوں کیونکہ وہ نہایت مہربان ہے
اور اپنی ذات پر توکل کرنے والوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا.وَ مِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ میں ایک وجود کے مبعوث ہونے کی طرف بھی اشارہ ہے جس کا
نام احادیث میں مہدی اور مسیح رکھا گیا ہے.اور بتایا گیا ہے کہ وہ ایسے وقت میں آئے گا جبکہ
مسلمانوں کے اندر سخت تفرقہ ہوگا اور ان کا اتحاد باقی نہ رہے گا.ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ جس
شخص کو دنیا کی اصلاح کے لئے کھڑا کرے گا لوگ اس کی شدید مخالفت کریں گے اور اس پر
حسد کریں گے.پس وَ مِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ میں یہ اشارہ بھی ہے کہ یہ دعا کرنی چاہئے کہ
اللہ تعالیٰ جب ایسے شخص کو مبعوث کرے تو اس کے حاسدوں میں سے نہ بنیں بلکہ اس کے
معاونین و انصار میں سے ہو کر خدا تعالیٰ کے فضلوں کے وارث ہوں.وہ مضامین جو اس سورۃ کے خلاصہ بیان کئے گئے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورۃ
اپنے مضمون کے لحاظ سے بہت اہم ہے اور امت مسلمہ کو بحیثیت قوم اور افراد کے ایک کامل
دعا اس سورۃ کے ذریعہ سے سکھائی گئی ہے.اور وہ اسباب جو قومی یا فردی طور پر تباہی کے پیدا
ہوسکتے ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے.اور یہ بتایا گیا ہے کہ انسان جب تک خدا تعالیٰ کی حفاظت
1130
Page 1139
میں نہ آئے اس دنیا میں خطرات سے محفوظ نہیں رہ سکتا.پس امن کا صحیح راستہ یہی ہے کہ انسان
ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کے آستانہ پر جھکا ر ہے اور اس کی حفاظت طلب کرے.ماخوذ از تفسیر کبیر - زیر تفسیر سورة الفلق)
حضرت خلیفہ امسیح الرابع رحمہ اللہ نے سورۃ الفلق کی تلاوت کے بعد فرمایا:
قرآن کا یہ بہت ہی پیارا اسلوب ہے کہ دعاؤں کے رنگ میں انسان کی تربیت فرماتا
ہے.دعاؤں سے جو فائدہ انسان کو پہنچتا ہے وہ اپنی جگہ ہے.اس کے علاوہ ان دعاؤں میں
بڑے گہرے مضامین ایسے ہیں جو انسان کی تربیت سے تعلق رکھتے ہیں.اس کے ذہن اور اس
کے قلب، اس کی فکر اور اس کے جذبات کو توازن بخشتے ہیں.اور وہ غلطیاں جن میں انسان
بسا اوقات مختلف جذبات اور مختلف مواقع پر مبتلا ہو جایا کرتا ہے ان غلطیوں کی نشاندہی کرتے
ہیں اور ان ٹھوکروں سے بچاتے ہیں.سورہ فلق کی یہ آیات جو میں نے تلاوت کی ہیں ان میں بھی ایک ویسی ہی بہت پیاری دعا
سکھائی گئی اور انسان کو ایک ایسے مضمون سے آگاہ کیا گیا کہ اگر وہ اس سے باخبر رہے تو
ترقیات اور فضلوں اور رحمتوں کے وقت بے خوف نہ ہو اور دنیا کی نظر میں جتنے خوف ہیں ان
خوفوں کے وقت مایوس نہ ہو.گویا ہر حالت میں انسان کو اعتدال کا سبق سکھایا گیا ہے.قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ غَيْرِ مَا خَلَق.فلق کہتے ہیں بیج کے پھوٹنے کو اور گٹھلیوں کے پھٹ کر ایک نئی کونپل پیدا کرنے کو، اور
رات کے صبح میں تبدیل ہونے کو.اور اس کے علاوہ اس کے برعکس معانی بھی فلق کے ساتھ
وابستہ ہیں.چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے :
إِنَّ اللهَ فَالِقُ الْحَبِ وَالنَّوَى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَي ذَلِكُمُ
اللهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ (الانعام 96)
دیکھو! إِنَّ اللهَ فَالِقُ الْحَب وَالتَّوَى اللہ بیجوں اور گٹھلیوں کو پھاڑ کرنئی زندگی پیدا کرنے والا
1131
Page 1140
خدا ہے.يُخْرِجُ الْحَقَّ مِنَ الْمَيِّتِ.اسی طرح وہ مردوں سے زندگی نکالتا ہے.لیکن اس حالت
سے بے خبر نہ رہنا کہ یہی مضمون برعکس صورت میں بھی ظاہر ہوتا ہے.وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ
الحتی.اور زندگی سے موت بھی نکلتی رہتی ہے.زندوں سے مردہ بھی پیدا ہوتے رہتے ہیں.اور
زندگی میں بھی تبدیلی ہوتی رہتی ہے.چونکہ فلق کے دونوں پہلو سامنے ہیں اس لئے جب بھی انسان کے لئے ترقیات کی نئی راہیں
کھلیں ، نئی صبحیں نمودار ہوں ، انسانی کوششوں اور محنتوں کا ثمرہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہو
اور وہ کوششیں پھوٹ کر کونپلوں میں تبدیل ہو رہی ہوں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس میں فخر کا
کوئی مقام نہیں.بے فکر ہونے کی کوئی بات نہیں.ایسے جشن منانے کی کوئی ضرورت نہیں جو
سطحی اور دنیا کے جشن ہوں.کیونکہ حقیقت میں ہر زندگی کے ساتھ ایک موت بھی لگی ہوئی ہوتی
ہے.ہر روشنی کے ساتھ کچھ اندھیرے بھی وابستہ ہوتے ہیں.ایسے موقع پر اپنے رب کے حضور
جھکنا چاہئے جو خالق ہے، جس نے خیر وشر کا یہ نظام پیدا فرمایا ہے.اور اس سے یہ عرض کرنی
چاہئے کہ اے اللہ! ہمیں اس زندگی کے نئے دور میں اس طرح داخل فرما کہ اس کے ہر شر سے
محفوظ رکھنا اور ہر خیر اور برکت ہمارے پہلے میں ڈال دینا.یہ ہے وہ مضمون جس کو بھلانے کے نتیجہ میں فتوحات کے وقت فخر پیدا ہو جاتے ہیں.ادنی ادنی نعمتوں کے حصول کے وقت انسان اپنی عاقبت سے بے نیا ز اور بے فکر ہوجاتا ہے.زندگی کے ایک پہلو کو حاصل کر کے زندگی کے دوسرے پہلو سے آنکھیں بند کر لیتا ہے.نعمت
کے طور پر اسے تھوڑی سی چیز ملے تو اس نعمت کے نتیجہ میں وہ خود مالک بن بیٹھتا ہے اور خدا
سے غافل ہو جاتا ہے.نتیجہ اس شر سے بے پرواہ ہو جاتا ہے جو نعمت کے ساتھ ملحق ہوتا ہے.اگر نعمت کا صحیح استعمال ہو تو انسان شر سے بچ جاتا ہے.اگر غلط استعمال ہوتو شر اس کے بعد لازماً
اس کے تعاقب میں آتا ہے.چنانچہ یہی وہ مضمون ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور رنگ
میں یوں بیان فرمایا ہے.وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَا بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُ
1132
Page 1141
كان يَئُوسًا (بنی اسرائیل 84) کہ ایسے گھڑ دلے لوگ ہوتے ہیں جو زندگی کے دونوں
پہلوؤں سے واقف نہیں ہوتے ، جو خدا تعالیٰ کی کائنات کے رازوں سے بے پرواہ ہو جاتے
ہیں، جب ہم ان کو نعمت عطا فرماتے ہیں ، أَعْرَضَ وَنَا بِجانبه ، اس کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ وہ
نعمت لینے سے انکار کر دیتے ہیں...ایک اور پہلو یہ ہے کہ ہم نعمت عطا کرتے ہیں اور وہ
أَعْرَضَ وَنَا بِجانبہ وہ انسان خود پرستی میں مبتلا ہو جاتا ہے اور دین سے اور شکر کا حق ادا کرنے
سے پہلو تہی کرتا ہے.ونا بجانبہ اور ہر چیز کو اپنی جانب ہی سمیٹ لیتا ہے.یعنی پہلو تہی اس
رنگ میں گویا ئیں ہی تھا، سب کچھ میرا ہی ہے اور کسی کا کوئی دخل نہیں.یعنی خدا تعالیٰ کی
رحمت سے گلیہ غافل اور اس کے شکر سے حلیہ غافل ہو جاتا ہے اور وہ نہیں جانتا کہ اس کے
بعد شر بھی آنے والا ہے ایسی حالتیں ہمیشہ شر لے کر آتی ہیں.نتیجہ وَإِذَا مَسَّهُ اللرُ كَانَ
يَمُوسًا.اس وقت بھی اس کی عجیب حالت ہوتی ہے.جب اس کو شر پہنچتا ہے تو ایسے شخص
میں مقابلہ کی طاقت نہیں ہوتی.وہ ایک کیفیت سے مغلوب ہونا جانتا ہے.یہ نفسیاتی فلسفہ ہے
جو قرآن کریم بیان کر رہا ہے کہ وہ لوگ جو زندگی کے دونوں پہلوؤں پر بیک وقت نظریں نہیں
رکھتے وہ ایک پہلو سے مغلوب ہو جاتے ہیں.جس طرح وہ خوشی سے مغلوب ہو جاتے ہیں اسی
طرح شر سے بھی مغلوب ہو جاتے ہیں.اور شر آ تا ہے تو زندگی سے مایوس ہو جاتے ہیں.ان کو
روشنی کی کوئی کرن نظر نہیں آتی.ان چیزوں سے پناہ کی تلقین فرمائی گئی.دعا سکھائی گئی.قُل
أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ اے خدا ! تو جونئی نئی امید میں پیدا کرنے والا اور ہمارے
لئے ترقی کے نئے راستے کھولنے والا ہے.تو ہماری کوششوں کے بیجوں کو نئے پودوں اور
لہلہاتی ہوئی کونپلوں میں تبدیل کرنے والا خدا ہے.تو زندگی کے اس عمل کے شر سے
ہمیں محفوظ رکھنا کیونکہ ہر پیدائش کے ساتھ کچھ شر بھی لگے ہوتے ہیں اور ہمیں موت سے
غافل نہ ہونے دینا.کیونکہ جس وقت زندہ چیز موت کے خطروں سے غافل ہو جاتی ہے وہ
ہمیشہ انحطاط پذیر ہو جاتی ہے.وَمِن شَرِ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ.اور رات کے خطروں سے بھی
1133
Page 1142
بچانا جب وہ چھا جائے.غَسَقَ الَّيْلُ کا مطلب ہوتا ہے رات جب اندھیری ہو جائے ، جب بھیگ جائے.چنانچہ
قرآن کریم نے اس مضمون کو دوسری جگہ خود واضح کیا.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے.أقيم الصَّلاةَ
لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ (بنى اسرائيل 79) کہ جب رات گہری ہو جائے اس
وقت بھی نماز پڑھا کرو.کیونکہ اس وقت خطرات سے بچنے کے لئے دعاؤں کی ضرورت ہوا
کرتی ہے.یہی مضمون ہے جو اس آیت میں بیان فرمایا وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ.اس
وقت کھڑے ہو جایا کرو عبادت کے لئے اور دعائیں کیا کرو کہ رات کے خطرات سے بھی
ہمیں محفوظ رکھنا.تُو نے ایک صبح امید تو پیدا فرمائی لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہر صبح کے ساتھ ایک
رات بھی وابستہ ہوا کرتی ہے.تو صبح کے وہ فضل تو لے کر آیا لیکن راتوں کے شر سے بھی
ہمیں محفوظ رکھنا.فَالِقُ الْإِصْبَاح کا یہ وہ مضمون ہے جس کی طرف قرآن کریم نے خود اشارہ کیا ہے.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَالِي الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنَّا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا
(الانعام (97) فَالِقُ الْإِصْبَاح تو وہ ہے.لیکن فلق کے بعد ایک رات بھی آیا کرتی
ہے.خدا کے مومن بندے جو اس کی طرف جھکنے والے ہیں اور اس کی یاد میں مبتلا رہتے ہیں ان
کے لئے وہ رات سکینت لے کر آتی ہے اور بے چینی اور بے فکری کوڈ ور کرنے والی ہوتی ہے.لیکن وہ لوگ جو اس نظام سے غافل ہوتے ہیں اور اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں وہی رات
ان کے لئے شر لے کر بھی آ جاتی ہے.تو فرمایا وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ.جب اندھیرے
آئیں گے تو ان کے شر سے بھی ہمیں محفوظ رکھنا.اندھیروں کے شر کیا ہیں ؟ اس کا بھی ان آیات میں ذکر ہے.اور اندھیرے کس کس قسم
کے آتے ہیں؟ ان کا بھی ان آیات میں ذکر ہے.ایک اندھیرے تو وہ ہیں جو روشنی کے نتیجہ میں
ایک رد عمل کے طور پر پیدا ہوتے ہیں.ایک اندھیرے وہ ہیں جو قانون قدرت کے مطابق دن
1134
Page 1143
اور رات کے آدلنے بدلنے کے نتیجہ میں پیدا ہوتے ہیں جو تِلْكَ الْآيَامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ
(آل عمران (14) کا مضمون لے کر آتے ہیں.یعنی خدا کی طرف سے ترقیات تو عطا ہوتی ہیں
لیکن جو قومیں ان ترقیات کا شکر ادا نہیں کرتیں وہی دن ان کے لئے راتوں میں تبدیل ہو جایا
کرتے ہیں.اور قوموں کی تاریخ کا خلاصہ یہی ہے کہ کبھی وہ عروج حاصل کر رہی ہیں، کبھی
زوال پذیر ہورہی ہیں.لیکن دنیا میں تو یہ ایک طبعی نظام کے طور پر ہمیں ملتا ہے کہ لازماً روشنی
کے بعد اندھیرے نے آنا ہے.مگر قرآن کریم کہتا ہے کہ وہ روشنیاں جو ہم مذہبی قوموں کو عطا
کیا کرتے ہیں ان کے بعد اندھیر الازم نہیں ہے.ہو سکتا ہے اور یہ ایک حد تک تمہارے اپنے
اختیار میں ہے کہ ان روشنیوں کا زمانہ لمبا کرلو.کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے : إِنَّ اللهَ لَا يُغَيْرُ مَا
بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيْرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ.وَإِذَا أَرَادَ اللهُ بِقَوْمٍ سُوْءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ.(الرعد12) کہ
خدا تعالیٰ نے ایک تقدیر بنادی ہے.یہ مبرم تقدیر ہے جوٹل نہیں سکتی.لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ جو
نعمتیں کسی قوم کو عطا فرماتا ہے ان
کو پھر تبدیل نہیں کیا کرتا.حَتَّى يُغَيْرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ یہاں
تک کہ وہ خود تبدیل ہونے لگتے ہیں.خود بلانے لگتے ہیں تباہی کو اور ہلاکت کو اور تنزل کو.اس وقت خدا کی ایک اور تقدیر ظاہر ہوتی ہے اور ان کے اعمال
کا نتیجہ ان کے سامنے پیش کیا
جاتا ہے.فرماتا ہے وَإِذَا أَرَادَ اللهُ بِقَوْمٍ سُوْءٍ فَلَا مَر ذَلَہ پھر جب اللہ یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ
اس قوم کو برائی میں مبتلا کیا جائے گا.لَا مَرَد لَهُ اس فیصلہ کو کوئی ٹال نہیں سکتا.یہ بھی
اندھیرے ہوتے ہیں جو خدا کی عطا کردہ روشنیوں کے بعد آتے ہیں.لیکن ان اندھیروں میں
بندوں کا دخل ہے.وہ کوئی ایسا نظام نہیں ہے جو ٹالا نہیں جاسکتا.اس کے برعکس کچھ ایسے اندھیرے ہیں جو روشنیوں کے نتیجہ میں ازخود پیدا ہو جاتے ہیں.ان کا بھی قرآن کریم میں بلکہ اسی آیت میں ذکر ہے.وہ اندھیرے ہیں ترقی کے نتیجہ میں حسد
کی پیداوار.اور وہ اندھیرے مومن کی خوشی کی تقریب کے ساتھ ساتھ لاز ما چلتے ہیں.وہ خدا کی
طرف سے عائد کردہ اندھیرے نہیں ہیں بلکہ خدا کے دشمنوں کی طرف سے عائد کردہ اندھیرے
1135
Page 1144
ہیں.چنانچہ فرما یا مِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ.وَمِن شَرِ النَّقْفتِ فِي الْعُقَدِ کہ ان اندھیروں
سے مراد یہ ہے کہ جب تم خدا تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہوئے آگے بڑھو گے اور اس کی
تبدیلیوں کے نظام میں ہر خیر سے کوئی برکت پانے لگو گے لیکن ہر شر سے محفوظ رہو گے تو اس
کے نتیجہ میں دشمن پر کچھ اندھیرے طاری ہو جائیں گے اور ان اندھیروں کے نتیجہ میں وہ تم پر بھی
اندھیرے طاری کرنے کی کوشش کریں گے.ومِن شَرِ النَّقْفتِ فِي الْعُقَدِ تمہارے جو
تعلقات قائم ہوں گے، تمہارے جو روابط پیدا ہوں گے، دنیا میں تم ہر دلعزیز ہو گے، نئی نئی
قوموں سے تمہارے واسطے پیدا ہوں گے، ایسے تمام مواقع پر اللہ تعالیٰ مطلع فرماتا ہے کہ کچھ
ایسے بھی پیدا ہوں گے جو ان تعلقات کو توڑنے کے لئے ان میں زہر گھولنے کے لئے پھونکیں
ماریں گے.نقفت کہتے ہیں پھونکنے والیوں کو.یعنی جادوٹو نا کرنے والیوں کو بھی نظفت کہا جاتا ہے.لیکن نفت کا اصل مضمون سانپ سے تعلق رکھتا ہے.چنانچہ اسی مضمون سے آگے پھر جادوٹونے کا
مضمون مستعار لیا گیا.افعی یعنی سانپ جب زہر گھولتا ہے، گس گھولتا ہے تو اس کو عربی میں نفت
کہتے ہیں.(اقرب الموارد زیر لفظ نفث) فرمایا ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور نعمتیں ہیں جو
تمہارے لئے زندگی کا انتظام کر رہی ہوں گی.دوسری طرف موت تھوکنے والے بھی پیدا ہو جائیں
گے جو تمہارے تعلقات کی گانٹھوں میں موت پڑھ پڑھ کر پھونکیں گے یا موت کا زہر گھولنے کی
کوشش کریں گے.اللہ تعالیٰ متنبہ فرماتا ہے کہ یہ خطرات وابستہ ہیں.یہ وہ خطرات ہیں جو
تمہارے مقدر میں ہیں.ان کو کوئی ٹال نہیں سکتا.ہاں اگر تم دعائیں کرو گے تو ان خطرات کے
وقت ان کے شر سے محفوظ رہو گے.یعنی یہ رات تو ایسی ہے جو ٹل نہیں سکتی.لازما آنی ہے.اندھیروں کی یہ پیداوار کہ سانپ بچھو نکل آئیں اور ڈسنے لگیں ، چور ڈا کو اور اچھکے پیدا ہوجائیں ، یہ تو
ایک ایسی قدرت خداوندی ہے جس کو کوئی بدل نہیں سکتا.فرمایا ہاں ایک چیز ہے جو ہمارے بس
میں ہے.یہ سانپ تھوکتے رہیں گے تمہاری گانٹھوں پر.اللہ ان کے شرسے تمہیں محفوظ رکھتا
1136
Page 1145
چلا جائے گا.یہ وہ تقدیر ہے جس کو حاصل کرنے کے لئے تم دعائیں کرو.پھر فرماتا ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ اگر کوئی ان تمام احتیاطوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ
کے فضلوں اور رحمتوں کے راستہ پر آگے بڑھتا چلا جائے تو خدا تعالیٰ اپنے فضل اتنے بڑھائے
گا اور شر سے اس طرح محفوظ رکھتا چلا جائے گا کہ ہر قدم حصول خیر و برکت کا قدم تو ہوگا.ٹھوکر
اور تنزل کا قدم نہیں ہوگا.جب تم اس مقام پر پہنچو گے تو ایک اور قسم کا اندھیرا بھی تمہاری راہ
میں منتظر ہوگا اور وہ حاسد کا حسد ہے.تقُفتِ فِي الْعُقد کے بعد حاسد کے حسد کا مضمون رکھا گیا.یہ کیوں ہے؟ بظاہر انسان یہ سمجھتا
ہے کہ حاسد کے حسد کے نتیجہ میں ہی تو وہ پھونکیں ماری جائیں گی.لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ
یہاں ایک اور مضمون بیان ہو رہا ہے.مراد یہ ہے کہ دشمنوں پر دود ور آتے ہیں.ایک نفرت
اور حقارت کا وہ دور جب کہ وہ خدا تعالیٰ کے قافلوں کی راہ میں حائل ہونے کی اور ان کے
تعلقات میں زہر گھولنے کی پوری کوشش کرتے ہیں لیکن وہ ناکام کر دئیے جاتے ہیں.جب
وہ قافلہ ان کوششوں کے باوجود آگے بڑھ جاتا ہے اور ترقی کی نئی نئی منازل طے کرتا چلا جاتا
ہے تو اس وقت حاسدوں کے حسد کی نظریں پڑتی ہیں اور وہ کچھ نہیں کرسکتیں.ایک
بے اختیاری کا عالم ہے ، غیظ و غضب کا عالم ہے لیکن بس کوئی نہیں ہوتا.لیکن اس حسد کے نتیجہ
میں بھی بعض دفعہ نقصانات پہنچ جاتے ہیں.کیا بار یک فلسفہ ہے اس حسد کا.اس وقت اس کی
تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے.لیکن حسد کے نتیجہ میں انسان تاک میں لگا رہتا ہے.بعد
کے مواقع میں اس کا غصہ بغض میں تبدیل ہو جاتا ہے.ایسے کینہ میں تبدیل ہو جاتا ہے جو اس کی
فطرت میں کس گھولنے لگ جاتا ہے بجائے اس کے کہ وہ آپ کے تعلقات میں کس گھولے.یعنی اندرونی مضمون ہے جس طرح سانپ کو ڈسنے کا موقع نہیں ملتا اور وہ طیش میں بیٹھا ہو کہ
میں نے ضرور ڈسنا ہے تو اہل علم جانتے ہیں کہ جتنی دیر اس کے زہر کی تھیلی کو انتظار میں لگتی ہے اتنا
ہی زیادہ زہر اس میں بھرتا چلا جاتا اور خطر ناک ہوتا چلا جاتا ہے.تم دعائیں کرو گے تو ہم تمہیں
1137
Page 1146
محفوظ رکھیں گے.تمہیں بالکل پرواہ نہیں کرنی چاہئے.جو خدا کے فضل ہیں ان فضلوں کو کوئی
تبدیل نہیں کر سکتا.صرف تم کر سکتے ہو ( یعنی اپنی بداعمالیوں کے ذریعہ ) اگر تم نہ بدلو گے تو میں
بھی نہیں بدلوں گا.تم میرے فضلوں اور رحمتوں کے وارث بنے رہو گے ، حق دار بنے رہو گے تو
میں فضل بڑھاتا چلا جاؤں گا اور دشمن کے زہر سے تمہیں محفوظ رکھوں گا.لیکن کچھ افعی ایسے بھی
رہ جائیں گے جن کا بس نہیں چلے گا.وہ ترقیات پر تمہیں گامزن دیکھیں گے تو وہ اپنے اندر گس
گھولنے لگیں گے.اپنے زہر کو بڑھاتے چلے جائیں گے.یہ ہے حسد کا مضمون جس پر جا کرتان ٹوٹی ہے اس سارے مضمون کی ، اور یہ ایک مستقل
بغض ہے جو پیدا ہوتا چلا جائے گا اور تمہاری ہر ترقی کے نتیجہ میں یہ بغض بڑھتا چلا جائے گا
خواہ ان کی کچھ پیش جائے یا نہ جائے.ایسے حاسد، ایسے کینہ ور انتظار میں لگے رہتے ہیں.کسی
جماعت سے یا کسی فرد سے کبھی غفلت ہو اس وقت ان کا داؤ چلتا ہے اور پھر وہ بڑی قوت کے
ساتھ ڈسنے کی کوشش کرتے ہیں.تو ایک دفعہ بچنے کے بعد ہمیشہ کے لئے غافل نہیں ہو
جانا.یہ نہ سمجھنا کہ آگے موت کسی پہلو سے بھی تمہارا انتظار نہیں کر رہی.وہ تو تمہاری تاک
میں بیٹھی رہے گی اور اس کو انتظار میں جتنی دیر لگے گی اتنا ہی اس کا زہر بڑھتا چلا جائے گا.اس
لئے قیامت تک کے لئے ہر دشمنی کے شر سے محفوظ رکھنے کی دعا سکھا دی گئی.کتنا عظیم الشان
کلام ہے.کوئی ایک پہلو بھی باقی نہیں چھوڑا جو ترقیات کی راہ پر چلنے والی قوموں کی راہ میں
پیش آسکتا ہے جس کا قرآن کریم نے یہاں ذکر نہ فرمایا ہو.سب سے پہلی بات جو بیان فرمائی گئی اس کے نتیجہ میں کچھ ذمہ داریاں بھی ہم پر عائد ہوتی
ہیں.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے.قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِن شَرِّ مَا خَلَق خالق ،اللہ ہے.تم نہیں
ہو.تم سمجھتے ہو کہ تمہاری کوششوں کے نتیجہ میں ایک چیز پیدا ہوئی.لیکن یہ جان لو کہ رَبُّ
الفلق صرف خدا ہے اُس کے سوا اور کوئی ذات نہیں.اگر تم یہ جان لو کہ خدا ہی ہے جو پیدا
کرنے والا ہے تو جھوٹے تکبر اور جھوٹے تفاخر تم میں پیدا ہی نہیں ہو سکتے.انکسار تو پیدا ہوسکتا
1138
Page 1147
ہے اس احساس کے بعد کہ ہماری کوششیں نہیں تھیں، اللہ کے فضل تھے.لیکن وہ کھوکھلی اور
ہلکی باتیں جو ان رازوں کو نہ سمجھنے والے دلوں میں پیدا ہو جاتی ہیں ہر ماحصل کے بعد ، ان
کھوکھلی باتوں سے مومن محفوظ رکھا جاتا ہے.خطبہ جمعہ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ فرمود وہ 15 اکتوبر 1985ء.خطبات طاہر جلد اوّل صفحہ 201 - 208)
حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے ماہ رمضان المبارک 2016ء
کے آخری روز مسجد فضل لندن میں قرآن مجید کی آخری تین سورتوں کا درس ارشاد فرمایا.حضور انور
ایدہ اللہ نے اس میں سورۃ الفلق کا درس دیتے ہوئے فرمایا:
حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس بارے میں فرماتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:
” کہہ میں شریر مخلوقات کی شرارتوں سے خدا کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں اور اندھیری رات سے
خدا کی پناہ میں آتا ہوں.اس کی وضاحت آپ نے یہ فرمائی.یعنی یہ زمانہ اپنے فساد عظیم کے
رُو سے اندھیری رات کی مانند ہے.رات جو چھا جاتی ہے وہ رات صرف مراد نہیں بلکہ جو زمانہ
ہے وہ گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، دنیا داری میں ڈوبا ہوا ہے.اس کے جو شر ہیں ان سے پناہ مانگتا
ہوں اور ایک فساد عظیم اس وجہ سے دنیا میں پیدا ہوا ہے.فرمایا ”سواہی قو تیں اور طاقتیں اس زمانہ
کی تنویر کے لئے درکار ہیں.انسانی طاقتوں سے یہ کام انجام ہونا محال ہے.“
66
( براہین احمدیہ حصہ چہارم ، روحانی خزائن جلد 1 صفحه 604 حاشیہ)
اب اللہ تعالیٰ نے تو یہ دعا اس لئے بتائی کہ مخلوقات کی شرارتیں ہر زمانے میں ہوتی ہیں اور
کوئی بھی اس سے محفوظ نہیں اور یہ زمانہ جس میں مسیح موعود کا ظہور ہونا تھا خاص طور پر اس بات
کا متقاضی تھا اور ہے کہ خدا تعالیٰ کی خاص پناہ تلاش کی جائے.اللہ تعالیٰ کی پناہ کے بھی ذرائع
ہیں.کس طرح وہ پناہ دیتا ہے؟ مختلف ذریعے ہیں.اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق اس فساد زدہ زمانے ، اندھیرے
زمانے،روحانیت سے دُور ہٹ کر اندھیرا پھیلنے کے زمانے کے لئے مسیح موعود کو بھیجا ہے
1139
Page 1148
جس نے اندھیروں سے نکال کر روشنی دکھانی ہے.اور ہر ایک جانتا ہے، اس میں کوئی شک
نہیں کہ یہ زمانہ فساد عظیم کی انتہا پہ پہنچا ہوا ہے.حکومتیں بھی آزادیوں کے نام پر گناہ کرنے
کے قانون پاس کرتی ہیں.اللہ تعالیٰ نے جو روشنی بھیجی ہے وہ مسیح موعود کی روشنی ہے.اور نہ ہی
دنیا دار نام نہاد دوسرے مذاہب، نہ ہی مسلمان جو اللہ تعالیٰ نے روشنی بھیجی ہے اس کو قبول کرنا
چاہتے ہیں.دونوں ہی اس روشنی کے انکاری ہیں.اس روشنی کو لینے کے لئے نہ آپ بند کمروں
سے باہر نکلنا چاہتے ہیں، نہ اپنی سوچوں کو کھولنا چاہتے ہیں کہ جو روحانیت جذب کرنے کا ذریعہ
بنے.منہ اپنے اندھیرے دلوں کی کھڑکیاں اور دروازے کھولنا چاہتے ہیں کہ روشنی ان میں داخل
ہو.ان لوگوں کو خیال یہ ہے کہ یہ دنیا کے فساد جو بظاہر نظر آ رہے ہیں قتل و غارت، جنگیں،
ماردھاڑ ، فتنہ و فساد یہ دنیاوی طریقوں سے دُور کرلیں گے.حقیقت تو اصل میں یہ ہے کہ یہ
لوگ تو خود ہی فساد پیدا کرنے والے ہیں.مسلمان ملکوں کو دیکھ لیں ان میں فرقہ واریت کی وجہ سے فساد پیدا ہوا ہوا ہے.طاقت کی
جنگ کی وجہ سے فساد پیدا ہوا ہوا ہے.مسلمان، مسلمان کا خون کر رہا ہے.حکومتیں فساد میں
حصہ دار ہیں.سعودی عرب ہے.ایران ہے.ترکی ہے.کویت ہے.یمن ہے.غرض کہ ہر
ملک میں فساد ہے.بیشمار ملک ہیں.مسلمان ہو کر ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ رہے ہیں اور
نام یہ ہے کہ ہم امن قائم کر رہے ہیں.دو دن پہلے عراق میں دھما کہ ہوا.دوسو کے قریب لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے.ٹی وی پر
دکھا رہے تھے لوگ رور ہے ہیں کہ کل ہماری عید ہے یا دو دن بعد عید ہے اور یہ عید ہے جو ہم
منائیں گے؟ اپنے رشتہ داروں کو خون میں ڈوبا ہوا دیکھ رہے ہیں.ان کو قبروں میں اتار رہے
ہیں.اور ستم ظریفی یہ کہ یہ قتل و غارتگری اسلام کے نام پر ہورہی ہے.دو چار دن پہلے بنگلہ دیش
میں اسلام کے نام پر بلاکتیں کی گئیں.مغربی ممالک میں اسلام کے نام پرخون کی ہولی کھیلی
جاتی ہے.گویا ان کے نزدیک اس سے اسلام پھیل رہا ہے اور اب اتنی جرات ہے کہ کل
1140
Page 1149
مسجد نبوی میں دہشت گردی کا واقعہ ہو گیا.چار پولیس والے مارے گئے.اگر دہشت گردوں
کو موقع مل جاتا تو مسجد نبوی کا بھی تقدس انہوں نے نہیں رکھنا تھا، وہاں بھی خون کی ہولی کھیلی
جانی تھی.بہر حال اللہ تعالیٰ کا فضل ہو گیا کہ لوگ محفوظ رہے.یہ سب کیا ظاہر کرتا ہے؟ یہی کہ
اندھیرا پھیل چکا ہے اس کے لئے الہی روشنی کی تلاش کرو.جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام
نے فرما یا دنیاوی وسیلوں اور انسانی طاقتوں سے یہ فساد عظیم رکنے والا نہیں کیونکہ نام نہاد امن
قائم کرنے والے بھی وہی ہیں اور فساد پیدا کرنے والے بھی وہی ہیں.گزشتہ دنوں UNO کی طرف سے ایک بیان دیا گیا کہ سعودی عرب یمن میں فساد کی
بہت بڑی وجہ ہے.اس کی وجہ سے فساد ہے.اس پر بجائے شرمندگی کے یا کسی ایسے اظہار
کے کہ ہم آئندہ نہیں کریں گے یا ہم نہیں کر رہے، کوئی شریفانہ بیان دیتے.انہوں نے کہا
کہ ٹھیک ہے تم نے یہ بات کی ہے.ہم UNO کو فنڈنگ کرنے میں کافی بڑے ڈونر
(doner) ہیں.ہم اس کو فنڈ (Fund) کرتے ہیں.ہم یہ UNO کی مدد بند کر دیں گے.تیل کا پیسہ جو ہے ہم یہ فساد پیدا کرنے کے لئے خرچ کر رہے ہیں.ان الفاظ میں تو نہیں کہا،
مطلب یہی تھا، اور یہ اسی طرح جاری رہے گا اور تمہیں جو دیتے ہیں، تمہارا منہ بند کرنے کے
لئے ، نام نہاد امن قائم کرنے کے لئے جو تنظیم بنائی گئی ہے اس کے بھی ہم فنڈ بند کر دیں گے.جس پر UNنے معذرت کی اور بان کی مون (Ban Ki-moon) صاحب جو ان کے
سیکرٹری جنرل ہیں انہوں نے کہا کہ گو ہے تو یہ حقیقت لیکن ہم مجبور ہیں کہ مالی مشکلات ہمیں
پیدا ہوسکتی ہیں اس لئے ہم اپنے الفاظ واپس لے لیتے ہیں کہ بیشک سعودی عرب فساد پیدا کر رہا
ہے اور نظر بھی آ رہا ہے لیکن ہمارے پیسے مارے جاتے ہیں اس لئے ہم کچھ کہہ نہیں سکتے.یہ ہیں انصاف کے معیار، انصاف کے تقاضے، فساد دور کرنے کی کوششیں جن کو یہ دنیاوی
ذرائع سے پورا کرنا چاہتے ہیں.اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں تم نہیں کر سکتے.اس کے لئے
الہی روشنی کی ضرورت ہے.اس کو تلاش کرو.1141
Page 1150
مسلمانوں کی یہ فساد کی حالت ہے اس کی وجہ سے مغربی دنیا کو مسلمانوں
کا بڑا تفصیلی تعارف
ہے کہ کون کون سے فرقے ہیں.کون سلفی ہے.کون وہابی ہے.کون کیا کرتا ہے.سلفیوں
کے کیا اپنے مقاصد ہیں.وہابیوں کے کیا مقاصد ہیں.سٹی کیا ہیں.شیعہ کیا ہیں.کس پر ظلم ہو
رہا ہے.کون کس طرح ظلم کرتا ہے.کون کس طرح جواب دیتا ہے.کون کس طرح فساد کرتا
ہے.کس طرح ان کی planings ہورہی ہیں.کون کون کس طرح کے ظلموں میں ڈوبا ہوا
ہے اور یہ بھی ان لوگوں کو پتا ہے کہ مسلمانوں کی اس کمزوری سے ہم نے کس طرح فائدہ اٹھانا
ہے، اپنے مقاصد کس طرح پورے کرنے ہیں.اسلام کے خلاف بھی اپنی جو کوششیں ہیں جو
دجالی منصوبہ بندیاں ہیں ان پر کس طرح عمل درآمد کروانا ہے اور مسلمان ملکوں کی دولت پر
کس طرح قبضہ کرنا ہے.پھر داعش ایک دہشت گرد تنظیم ہے.اس کی خلافت کے حوالے سے دنیا میں ایک خوف
پیدا کیا گیا ہے اور اس کو سپورٹ کرنے والے، اس کی مدد کرنے والے، اس پر سخت ہاتھ نہ
ڈالنے والے یا جو سخت ہاتھ ڈالنا چاہتے ہیں ان کو ہاتھ ڈالنے سے روکنے والے یہی طاقتیں ہیں.بہر حال یہ چیزیں رہیں گی جب تک کہ اللہ تعالی کی طرف سے بھیجے ہوئے فرستادے اور
خاتم الخلفاء کی بات نہیں سنتے.خلافت جو چلنی ہے وہ مسیح موعود کی خلافت ہے، اس کے علاوہ
کوئی نہیں.جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ الہی قوتیں اور طاقتیں اس زمانے کی
تنویر کے لئے درکار ہیں.اس زمانے میں اگر کوئی روشنی پھیلنی ہے تو الہی طاقتوں سے.پس یہ
روشنی اگر مل سکتی ہے تو الہی قوتوں کے ذریعہ سے، نہ کہ دنیاوی حیلوں کے ذریعہ سے.اور اس
کے لئے مسیح موعود کا ہاتھ پکڑے بغیر چارہ نہیں ، جو مرضی کوشش کرلیں.اللہ تعالیٰ نے تو مسلمانوں کو یہ دعا سکھائی کہ اس پھاڑ کے زمانے میں، تفرقہ بازی کے
زمانے میں، پھوٹ کے زمانے میں ، جنگوں کے زمانے میں، فساد کے زمانے میں، فرقوں
1142
Page 1151
میں بٹنے کے زمانے میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آجانا اور یہ لوگ جو ہیں بجائے اس کے کہ اس دعا
کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی پناہ تلاش کریں اس سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں.اگر
دنیائے اسلام میں امن قائم کرنا ہے، اگر اندھیروں سے روشنی کی طرف جانا ہے تو مسیح موعود اور
مہدی معہود کا ہاتھ پکڑ نا ضروری ہے اور پکڑنا ہوگا.اس کے علاوہ اب شرور سے بچنے کا اور کوئی
راستہ نہیں ہے.بیشک وَمِن شَرِ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ مسلمان پڑھتے تو ہیں لیکن روح نہیں.صرف منہ سے
الفاظ ادا کرتے ہیں.اندھیروں سے نکلنے کے بجائے اندھیروں میں گرتے چلے جارہے ہیں.ایک تو قتل و غارت گری کر رہے ہیں.دوسرے ہر برائی میں مبتلا ہیں.اخلاقی لحاظ سے دیوالیہ
ہو چکے ہیں.اندھیروں میں ڈوبے ہوئے ہیں.دنیاوی لالچوں نے دین کی جگہ لے لی ہے.آنے والے مسیح موعود کے خلاف جو کہہ سکتے ہیں کہتے ہیں اور جو تدبیریں اور مکر استعمال کر سکتے
ہیں کرتے ہیں.لیکن ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ساری اسلامی دنیا میں بے چینی پھیلی ہوئی ہے.کہیں بھی امن نہیں ہے.یہ نتیجہ دیکھ بھی رہے ہیں لیکن پھر بھی اس بات سے ہٹنا نہیں چاہتے.نام نہاد علماء دین کے نام پر فساد پیدا کر رہے ہیں اور ہر ایک ان کے پیچھے چل رہا ہے.اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ میں یہ دعا سکھائی تو ومن شر النففتِ فِي الْعُقَدِ کہ کر پہلے ہی تنبیہ کردی
تھی کہ ان سے بچنا.یہ لوگ تمہیں بدیوں اور برائیوں میں مبتلا کریں گے.بجائے فساد سے دُور
لے جانے کے فساد میں ڈبوئیں گے.اسلام کے خلاف جو قوتیں کام کر رہی ہیں وہ ان علماء کے عمل کی وجہ سے طاقت پکڑ رہی
ہیں.علماء جو ہیں، یہ نام نہاد علماء ان کو امت کے وسیع تر مفادات کا خیال نہیں.لیکن خیال ہے تو
صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے کے خلاف کس طرح منصوبہ بندی کرنی ہے، احمدیوں پر
ظلم کس طرح کرتا ہے.حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ :
1143
Page 1152
علمائے اسلام ہیں جو اپنی غلطی کو چھوڑ نا نہیں چاہتے اور نفسانی پھونکوں سے خدا کے فطری
دین میں عقدے پیدا کر دیتے ہیں...کسی مرد خدا کے سامنے میدان میں نہیں آ سکتے.صرف
اپنے اعتراضات کو تحریف تبدیل کی پھونکوں سے عقدہ لا یخل کرنا چاہتے ہیں، یعنی اصلی
عبارتوں اور الفاظ کو بدل کر کوشش کرتے ہیں کہ مسئلے جو پیدا ہوئے ہوئے ہیں یہ اور الجھتے
جائیں اور کبھی حل نہ ہوں.فرمایا کہ عوام کو ایسے چکر میں ڈالا ہوا ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آتی.ان
کا تو یہی جواب ہوتا ہے کہ علماء نے یہ کہہ دیا ، علماء ٹھیک کہتے ہوں گے.سوچنے سمجھنے کی
صلاحیتیں، جو دینی سوچ ہے، جو روحانی سوچ ہے وہ عوام کی اکثریت کی ختم ہو چکی ہے.اس
لئے کہ ان کے جو لیڈر ہیں جن کو انہوں نے اپنی طرف سے روحانیت پیدا کرنے کے لیڈر بنایا
وہ تو خود اندھے ہیں.خود اندھیروں میں ڈوبے ہوئے ہیں.حضرت مسیح موعود علیہ السلام
فرماتے ہیں کہ ”...وہ قرآن کے مکذب ہیں کہ اس کی منشاء کے برخلاف اصرار کرتے ہیں
اور اپنے ایسے افعال سے جو مخالف قرآن ہیں...دشمنوں کو مدد دیتے ہیں...پس ہم ان کی
شرارتوں سے خدا کی پناہ مانگتے ہیں.“
(تحفہ گولڑویہ، روحانی خزائن جلد 17 صفحہ (221)
پھر وَمِنْ شَيْرِ النَّقْفتِ فِي الْعُقَدِ میں ان کے شر بھی شامل ہیں جو جماعت میں فتنہ پیدا کرنا
چاہتے ہیں.بعض ایسے لوگ ہمارے اندر بھی بعض دفعہ ہوتے ہیں جو کبھی حضرت مسیح موعود
علیہ السلام کے اقتباسات کے حوالوں سے بعض باتیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی
خلفاء کا مقابلہ کر کے.تو ان فتنوں سے بھی جماعت کے افراد کو بچنا چاہئے.پھر اس سورۃ میں حسد سے بچنے کی دعا سکھائی گئی.اسلام کی ترقی جو مسیح موعود کے ذریعہ ہونی
تھی اور آپ کے جاری نظام خلافت کے ذریعہ ہوئی تھی اور ہورہی ہے اس پر بھی حاسدوں کو
حسد ہے اور جوں جوں جماعت ترقی کرتی جائے گی یہ حسد بڑھتی جائے گی.آجکل افریقن ممالک میں جہاں جماعت اللہ تعالیٰ کے فضل سے پھیل رہی ہے
1144
Page 1153
سعودی عرب اور کویت کے علماء اور پاکستانی علماء پہنچ جاتے ہیں.روپیہ پیسہ تو وہاں کی حکومتوں
کا خرچ ہوتا ہے جو یہ علماء کو دیتے ہیں.تیل کا پیسہ ہے سعودی عرب کے پاس بھی، کویت کے
پاس بھی تو یہ بے انتہا خرچ کر رہے ہیں.وہ لوگ جو پہلے عیسائی تھے یالا مذہب تھے یا صرف
نام کے مسلمان تھے.نہ کسی کو کلمہ پوری طرح پڑھنا آتا تھا اور نماز کا تو سوال ہی نہیں، قرآن کا
تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا.ہمارے مبلغین معلمین نے جاکے ان کو کلمہ سکھایا.جومسلمان تھے
انہیں نما ز سکھائی ، قرآن پڑھنا سکھایا اور جو غیر مسلموں میں سے مسلمان ہوئے ان کو بھی مسجدیں
بنا کر دیں.بڑی غریبانہ چھوٹی سی مسجدیں بناتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں ہر جگہ بن
جائے.تو یہ لوگ وہاں پہنچ جاتے ہیں.وہاں کے مقامی غیر احمدی مولویوں اور اماموں کو پیسے
دیتے ہیں کہ یہاں سے احمدیت کے قدم اکھاڑنے کی کوشش کرو ہم تمہیں بہتر اور بڑی مسجد
بناکے دیتے ہیں.بہر حال اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ یہ مقامی لوگ اکثر ان میں سے ان پڑھ
ہیں لیکن الہی نور کی روشنی ان
کو پہنچ چکی ہے اس لئے ان کے دل روشن ہو چکے ہیں وہ خود ہی ان
کو جواب دیتے ہیں کہ ہمیں تو کلمہ پڑھنا تک نہیں آتا تھا.اس وقت تو تمہیں ہوش نہیں آئی.ہمارے بچوں کو کوئی قاعدہ نہیں پڑھاتا تھا، قرآن نہیں پڑھاتا تھا.اس وقت تو تمہیں ہوش
نہیں آئی.آج جب ہمارے لئے یہ انتظام ہو گیا ہے، ہمارے بچوں کو قرآن کریم پڑھنا سکھایا
جا رہا ہے، ہم بڑے جو ہیں ہمیں قرآن کریم پڑھنا سکھایا جا رہا ہے، ہمیں اسلام کی حقیقت بتائی
جا رہی ہے اور دین کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا کی گئی ہے.اب تم آ گئے ہو کہ یہ لوگ
مسلمان نہیں اور تم مسلمان ہو.تو بہر حال خود یہ مقامی لوگ ہی اکثر جگہ پر ان کا مقابلہ کرتے ہیں،
ان کا منہ بند کر دیتے ہیں.پس حاسدوں کے حسد کے شر سے بچنے کے لئے اس سورۃ کے پڑھنے کا حکم ہے.یہ
برداشت نہیں کر سکتے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغ دنیا کے کناروں تک پہنچے.پھر یہ حسد صرف مسلمانوں کی حد تک نہیں ہے.صرف اتنی نہیں کہ مسلمانوں میں محدود ہو.1145
Page 1154
ترقی یافتہ ملکوں میں بھی جب جماعت کی ترقی ہوگی تو یہاں بھی حسد کی آگ بھڑ کے گی.چھوٹے چھوٹے تجربے تو ہمیں ہونے شروع ہو گئے.مغربی ممالک میں بھی بعض جگہ سے
رپورٹس آتی ہیں کہ جب ہم چرچوں میں جا کر فنکشن کرتے ہیں تو شروع میں تو چرچ بڑی خوشی
سے ہمیں موقع دیتے ہیں.لیکن جب بار بار وہاں جاؤ اور دو تین دفعہ لگا تار جانے کے بعد جب
لوگوں کی توجہ اسلام کی طرف پیدا ہوتی دیکھتے ہیں تو مخالفت شروع کر دیتے ہیں اور حسد کی
آگ جاگ جاتی ہے.اور وہاں پھر اکثر یہ ہوا کہ جماعت کو جگہ دینے سے انکاری ہو گئے.(ماخوذ از هفت روزه افضل انٹرنیشنل 17 فروری 2017، صفحہ 14-15)
حضرت خلیفة المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے ماہ رمضان المبارک 2017ء
کے آخری روز قرآن مجید کی آخری تین سورتوں کا درس دیتے ہوئے فرمایا کہ :
مسلمان سورۃ الفلق پڑھتے ہیں لیکن اس کی گہرائی پر غور نہیں کرتے.حضرت مسیح موعود
علیہ السلام سورۃ الفلق کے مضمون کی وضاحت کرتے ہوئے ایک جگہ فرماتے ہیں کہ کہہ میں
شریر مخلوقات کی شرارتوں سے خدا کی پناہ میں آتا ہوں اور اندھیری رات سے خدا کی پناہ میں
آتا ہوں یعنی یہ زمانہ اپنے فساد عظیم کی رُو سے اندھیری رات کی مانند ہے سو الہی قوتیں اور
طاقتیں اس زمانے کی تنویر کے لئے درکار ہیں.اس زمانے میں اگر کوئی روشنی حاصل کرنی
ہے تو دنیاوی طاقتوں سے نہیں ملے گی اس کے لئے الہی قوتیں چاہئیں.فرمایا کہ انسانی
طاقتوں سے یہ کام انجام ہونا محال ہے.اس طرح آپ نے فرمایا کہ اس سورۃ میں اس
تار یک زمانے سے خدا کی پناہ مانگی گئی ہے جب لوگ خدا کے مسیح کو دکھ دیں گے.تو یہ
مسلمانوں کی حالت بھی بیان فرما دی، غیروں کی بھی حالت بیان فرما دی.مسلمانوں کی طرف
سے سب سے زیادہ خدا کے میسیج کو دکھ دیا گیا اور پھر یہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں وہ شان و شوکت
بھی دوبارہ حاصل ہو جائے جو پہلے حاصل تھی، وہ نور بھی حاصل ہو جائے جو پہلے حاصل تھا.آپ نے فرمایا کہ اس کے لئے الہی قوتیں درکار ہیں.اللہ تعالیٰ کی طاقت کے بغیر وہ نور
1146
Page 1155
حاصل نہیں ہوسکتا.اللہ تعالیٰ تو یہ دعا بتا رہا ہے کہ جب تاریک زمانہ آئے گا یعنی وہ زمانہ جب
اسلام کے خلاف سازشیں ہوں گی.ایک زمانہ تھا جب اسلام کے خلاف سازشیں ہوئیں جب
علمی اور اعتقادی لحاظ سے اسلام کو کمزور کرنے کے لئے حملے ہوئے.تو اللہ تعالیٰ نے اپنے
وعدے کے مطابق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھیجا اور آپ نے ان کے جو بھی علمی اور
اعتقادی اعتراضات تھے ان کو رڈ کیا اور ایسا جواب دیا کہ اسلام دشمنوں کو میدان سے بھاگنے
کے علاوہ کوئی چارہ نہ رہا.پھر دہریت کے حوالے سے حملے ہوئے تو حضرت مسیح موعود علیہ
السلام نے اس کے بھی جواب دئیے.آپ کے لٹریچر میں ، کتب میں وہ جواب موجود ہیں.اب اسلام دشمن طاقتیں نئے رنگ اور نئے دجل کے ساتھ اور نئے طریق لے کر اسلام پر حملہ
آور ہونے کی کوشش کر رہی ہیں تو اس کا جواب بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے
پہلے ہی دے دیا.ہمیں سمجھا دیا اور آپ کے لٹریچر میں ہمیں یہ ملتا ہے.آپ کی کتب میں ملتا
ہے.حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہ فرمایا کہ الہی قوتیں اور طاقتیں اس زمانے
کی تنویر کے لئے درکار ہیں تو یہ الہی قوتیں اس زمانے میں خدا تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود
علیہ السلام کے ذریعہ اتاریں.اس لئے یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کی تعلیم سے ہٹ کر
یا آپ سے ہٹ کر کوئی اور قوت اس اندھیرے کو دور کر سکے.حضور نے فرمایا کہ اعتقادی اور علمی جنگ میں آپ نے دشمنوں کو شکست دی جیسا کہ میں
نے بتایا.جو یہ کہتے تھے خدا تعالیٰ کا بیٹا ہے اور مسلمان اس پر ایمان لانا بھی شروع ہو گئے
تھے.اس زمانے میں لاکھوں مسلمان عیسائی ہو گئے.آپ نے دلائل سے مخالفین اسلام
کے، دشمنوں کے منہ بند کر کے مسلمانوں کو اس سے بچایا.اب چاہے حضرت مسیح موعود علیہ
الصلوۃ والسلام پر یہ لوگ کفر کے فتوے لگائیں لیکن اُس وقت کے علماء بھی اور اِس زمانے
کے بعض علماء بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو قرآن کریم کا بھی
بہت وسیع علم حاصل تھا اور بائبل کا بھی بڑا وسیع علم حاصل تھا اور دوسرے مذاہب کا بھی بڑا وسیع
1147
Page 1156
علم حاصل تھا جس کی وجہ سے آپ نے اسلام کے مخالفین کے منہ بند کر دیئے.اب چاہے
مولوی جو کہتے رہیں لیکن بہر حال مخالفین اسلام کا مقابلہ کرنے کے لئے جس روشنی کی ضرورت
ہے وہ مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعہ ہی اتری ہے لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مخالفت
کی وجہ سے یہ لوگ اسلام کو کمزور کر رہے ہیں.کیونکہ جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے
ایک جگہ فرمایا کہ یہ زنانہ خصلت لوگ ہیں اور فتنہ ان کی فطرت میں ہے.آپ فرماتے ہیں
کہ وہ علمائے اسلام جو اپنی غلطی کو چھوڑنا نہیں چاہتے اور نفسانی پھونکوں سے خدا کے فطری دین
میں عقدے پیدا کر دیتے ہیں اور زنانہ خصلت رکھتے ہیں کہ کسی مرد خدا کے سامنے میدان میں
نہیں آسکتے صرف اپنے اعتراضات کو تحریف تبدیل کی پھونکوں سے عقدہ لا یخل کرنا چاہتے
ہیں.اسلام کی تعلیم کو بھی انہوں نے بگاڑ دیا اس میں تحریف کر رہے ہیں اور ایسی ایسی تفسیریں
اور تشریحیں کر رہے ہیں، ایسے مسائل انہوں نے پیدا کر دئیے ہیں ان اعتراضوں کی وجہ سے
کہ جو بظاہر لگتا ہے کہ حل ہی نہیں ہو سکتے اور یہی وہ لوگ چاہتے ہیں.پس اصل میں تو اناؤں
اور نفسانی خواہشات کی وجہ ہے جس کی وجہ سے ان علماء نے اُمتِ مسلمہ کو غلط راستے پر ڈالا
ہوا ہے.کہیں بھی چلے جائیں کوئی دلیل ان علماء کے پاس احمدیت کے رڈ کرنے اور حضرت
مسیح موعود علیہ السلام کے دعوے کو رڈ کرنے کے لئے نہیں ہے.اب الجزائر میں بہت زیادہ
مخالفت کی لہر اٹھی ہے یہ بھی ان نام نہاد علماء کی وجہ سے ہی ہے.پس حضرت مسیح موعود
علیہ السلام نے فرمایا کہ ان لوگوں سے پناہ کے لئے اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھاتی ہے اس لئے یہ
دعا بہت کرو کہ ہم ان شرارتوں سے خدا کی پناہ مانگتے ہیں اور نیز ہم ان لوگوں کی شرارتوں سے
خدا کی پناہ مانگے ہیں جو حسد کرتے ہیں اور حسد کے طریقے سوچتے ہیں اور ہم اس وقت سے پناہ
مانگتے ہیں جب وہ حسد کرنے لگیں.پس یہ لوگ حسد کرنے والے، حسد کے نئے نئے طریقے
سوچنے والے لوگ ہیں اور اس کے لئے ہمیں دعا کرنی چاہئے اور اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کی
کوشش کرنی چاہئے.1148
Page 1157
حضور انور نے نہایت درد اور کرب کے ساتھ بیان فرمایا کہ کس طرح مسلمان مسلمان کا
خون کر رہا ہے.اور اس ضمن میں پاکستان، عراق، شام کے حالات کا ذکر فرمایا.اسی
طرح گزشتہ سال مسجد نبوی پر دہشتگر دحملہ کی کوشش کا ذکر فرمایا.حضور نے فرمایا کہ پھر اسلام کے نام پر یہاں مغربی ممالک میں دہشتگردی اور قتل و
غارت گری ہو رہی ہے اور اس کو دیکھ کر اسلام مخالف طاقتوں کو موقع مل رہا ہے کہ اسلام کو
بد نام کریں.اسلام کو دہشتگردی کا مذہب قرار دیں.اسلام کو امن وسلامتی کا دشمن قرار دیں.اس کے لئے بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری پہلے سے رہنمائی فرما دی کہ
جہاد کے نام پر جو ظلم و بربریت ہو رہی ہے یہ قرآنی تعلیم کے خلاف ہے.اس لئے جو بھی یہ عمل
کرتا ہے وہ اسلامی تعلیم کے خلاف کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک موجب سزا ہے.پس
حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے بجڑنے کی وجہ سے احمدی ہی ہیں جو ہر میدان میں
کھلی کھلی براہین اور دلائل سے اسلام کے دشمن کے منہ بند کر سکتے ہیں.یہ بات واضح کرتی ہے
کہ اس اندھیرے زمانے میں کسی الہی روشنی کی ضرورت ہے.یہ سب فساد جو مسلمان ملکوں میں
ہو رہا ہے یہ ظاہر ہے الہی روشنی کو چاہتا ہے.اور اللہ تعالیٰ نے جب یہ دعا سکھائی ہے تو یہ بھی
ایک طرح کی پیشگوئی تھی کہ زمانہ آئے گا اور آتا رہے گا کہ جب یہ اندھیرے پھیلتے رہیں گے
اور ان اندھیروں میں تم لوگ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کی کوشش کرنا.لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ
نے جب یہ دعا سکھائی یا پیشگوئی فرمائی تو پھر اس الہی روشنی کا انتظام بھی کر دیا.حضور انور نے فرمایا کہ پس یہ لوگ چاہے کسی ظاہری دنیاوی پناہ گاہ کی طرف جائیں یا
کوئی اور حیلہ تلاش کریں جب تک اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرستادہ کی بات نہیں مانیں گے
کسی صورت میں ان کے ملکوں میں، ان کی حکومتوں میں، آپس میں فرقوں میں، محبت اور
پیار اور امن کی فضا پیدا نہیں ہو سکتی.مسلمان ممالک کے اندر بھی فتنے اٹھتے رہیں گے.آپس
میں بھی یہ لڑتے رہیں گے.ملکوں کے اندر بھی فتنے ہوں گے اور ملک ملک سے بھی لڑیں گے.1149
Page 1158
حضور انور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا جو سورۃ الفلق میں ہے اس لئے سکھائی تھی کہ
اس پھاڑ کے زمانے میں، فرقوں میں بٹنے کے زمانے میں، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آجانا اور اس
شخص کے ساتھ جڑ جانا جسے اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا ہے کہ سب مسلمانوں کو جوڑوئے زمین پر
ہیں جمع کرو علی دِین واحد.پس اگر طاقت پکڑنی ہے، اگر دجال کا مقابلہ کرنا ہے، اگر
یاجوج ماجوج کے فتنوں اور ان کی خدائی سے نکل کر خدائے واحد کی پناہ میں آنا ہے تو پھر
حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ پکڑے بغیر کوئی چارہ نہیں.شرور سے بچنے کے لئے،
حاسدوں کے حسد سے بچنے کے لئے ، اس راستے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے.منہ سے
وَمِن شَرِ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ پڑھنے اور اس کی روح کو نہ سمجھنے کی وجہ سے مسلمان اندھیروں میں
گرتے چلے جا رہے ہیں.ہر ظلم اور ہر برائی کے اندھیروں میں گرتے چلے جارہے ہیں.اب
اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ مسلمان بدنام ہیں.دنیا دار حکومتوں اور ان کی آسائشوں کو
روشنی اور ترقی اور اپنی بقا سمجھتے ہیں لیکن حقیقت میں اس وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ سے دُور جارہے ہیں
اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا موجب بن رہے ہیں.پس اس شر سے بچنے کے لئے ان مسلمانوں کو سوچنا ہوگا اور ہم احمدیوں کو بھی کوشش کرنی
ہوگی کہ جہاں اس مضمون کو سمجھیں شیر النفقت سے اپنے آپ کو بھی بچائیں اور دنیا کو بھی
بچائیں.پھر حسد سے بچنے کے لئے بھی دعا کی طرف توجہ دیں کیونکہ اس کی بھی بہت ضرورت
ہے.حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ بڑا اہم نکتہ ہے کہ الہی روشنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام
کے ذریعہ سے ہی ہونی ہے اور پھر اس کے بعد کیونکہ آپ کے نظام نے ہی جاری رہنا ہے.نظام خلافت اس کا ذریعہ ہے.حاسدوں کی حسد اس کے لئے بھی بڑھے گی کہ کسی طرح
خلافت کو بھی نقصان پہنچایا جائے.جماعتی ترقی کے ساتھ خلافت کے نظام کے خلاف بھی حسد
بڑھتی جائے گی.پس ہر احمدی کو اس لحاظ سے بھی دعا بھی کرنی چاہئے اور اپنا خلافت سے پختہ
تعلق بھی پیدا کرنا چاہئے.1150
Page 1159
حضورانور نے فرمایا کہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کے بارے میں حضرت مسیح موعود
علیہ السلام نے خود بھی لکھا ہے کہ یہ خاص طور پر مسیح موعود کے زمانے سے تعلق رکھنے والے
مسائل اور حالات سے متعلق ہیں اور ان کا حل ہیں.اس لئے ہر احمدی کو اس کی گہرائی کو سمجھنا
چاہئے اور باقاعدگی سے پڑھنا چاہئے.(ماخوذ از افضل انٹرنیشنل 14 جولائی 2017 صفحہ 16 - 17 )
1151
Page 1161
XXXXXXXXXX
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ )
سورة الناس
1 - (میں) اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا
( اور ) بار بار رحم کرنے والا ہے ( پڑھتا ہوں)
2.ہم ہر زمانہ کے مسلمان سے کہتے ہیں کہ) تو
( دوسرے لوگوں سے ) کہتا چلا جا کہ میں تمام انسانوں
کے رب سے ( اس کی ) پناہ طلب کرتا ہوں.3 - ( وہ رب ) جو تمام انسانوں کا بادشاہ (بھی) ہے.4.اور تمام انسانوں کا معبود ( بھی ) ہے.مَلِكِ النَّاسِ في
الهِ النَّاسِ )
مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ
5.میں اس کی پناہ طلب کرتا ہوں ) ہر وسوسہ ڈالنے
والے کی شرارت سے.جو ( ہر قسم کے وسوسے ڈال
کر ) پیچھے ہٹ جاتا ہے.الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ) 6.( اور ) جو انسانوں کے دلوں میں شبہات پیدا کر
مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ
دیتا ہے.7.خواہ وہ ( فتنہ پرداز ) مخفی رہنے والی ہستیوں میں
سے ہو خواہ عام انسانوں میں سے ہو.1153
Page 1162
حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں:
قرآن شریف کے اول یعنی سورت فاتحہ کو وَلَا الضَّالین پر ختم کیا.یہ امر تمام مفسّر
با تفاق مانتے ہیں کہ ضالین سے عیسائی مراد ہیں اور آخر جس پر ختم ہواوہ یہ ہے قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ
النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي
صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ.سورۃ الناس سے پہلے قُلْ هُوَ اللہ میں خدا تعالیٰ کی توحید بیان فرمائی اور اس طرح پر گویا
تثلیث کی تردید کی.اس کے بعد سورۃ الناس کا بیان کرنا صاف ظاہر کرتا ہے کہ عیسائیوں کی
طرف اشارہ ہے.پس آخری وصیت یہ کی کہ شیطان سے بچتے رہو.یہ شیطان و ہی نحاش ہے
جس کو اس سورت میں خناس کہا ہے.جس سے بچنے کی ہدایت کی.اور یہ جو فرمایا کہ رب کی
پناہ میں آؤ اس سے معلوم ہوا کہ یہ جسمانی امور نہیں ہیں بلکہ روحانی ہیں.خدا کی معرفت،
معارف اور حقائق پر پکے ہو جاؤ تو اس سے بچ جاؤ گے.اس آخری زمانہ میں شیطان اور آدم کی
آخری جنگ کا خاص ذکر ہے.شیطان کی لڑائی خدا اور اس کے فرشتوں سے آدم کے ساتھ ہو کر
ہوتی ہے.اور خدا تعالیٰ اس کے بلاک کرنے کو پورے سامان کے ساتھ اترے گا اور خدا کا
مسیح اس کا مقابلہ کرے گا.یہ لفظ شیح ہے جس کے معنے خلیفہ کے ہیں عربی اور عبرانی میں.حدیثوں
میں مسیح لکھا ہے اور قرآن شریف میں خلیفہ لکھا ہے.غرض اس کے لئے مقدر تھا کہ اس آخری
جنگ میں خاتم الخلفاء جو چھٹے ہزار کے آخر میں پیدا ہو ، کامیاب ہو.الحکم جلد 6 نمبر 25 مورخہ 17 جولائی 1902 صفحہ 6)
سورة تبت میں غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ کے فتنہ کی طرف اشارہ ہے اور ولا
الضالين کے مقابل قرآن شریف کے آخر میں سورہ اخلاص ہے اور اس کے بعد کی
1154
Page 1163
دونوں سورتیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ان دونوں کی تفسیر ہیں.ان دونوں سورتوں میں اس
تیرہ و تار زمانہ سے پناہ مانگی گئی ہے جبکہ مسیح موعود پر کفر کا فتویٰ لگا کر مَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ کا فتنہ
پیدا ہوگا اور عیسائیت کی ضلالت اور ظلمت دنیا پر محیط ہونے لگے گی.پس جیسے سورت فاتحہ میں
جو ابتدائے قرآن ہے ان دونوں بلاؤں سے محفوظ رہنے کی دعا سکھائی گئی ہے.اسی طرح قرآن
شریف کے آخر میں بھی ان فتنوں سے محفوظ رہنے کی دعا تعلیم کی تا کہ یہ بات ثابت ہو جاوے کہ
اول بآخر نسبتی دارد.( الحکم جلد 6 نمبر 8 مورخہ 28 فروری 1902 ، صفحہ 5،4)
ناس کا لفظ صرف گروہ پر بولا جاتا ہے سو جو گروہ شیطان کے وساوس کے نیچے چلتا ہے وہ
دنبال کے نام سے موسوم ہوتا ہے.اسی کی طرف قرآن شریف کی اس ترتیب کا اشارہ ہے کہ
وه الْحَمْدُ لِلهِ رَبّ العلمین سے شروع کیا گیا اور اس آیت پر ختم کیا گیا ہے.الذی
ا
يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ.پس لفظ ناس سے مراد اس جگہ بھی دجال
سوره
ہے.ماحصل اِس سورۃ کا یہ ہے کہ تم دجال کے فتنہ سے خدا تعالی کی پناہ پکڑو.اس سورۃ سے پہلے سورۃ اخلاص ہے جو عیسائیت کے اصول کے رڈ میں ہے.بعد اس کے
رہ فلق ہے جو ایک تاریک زمانہ اور عورتوں کی مکاری کی خبر دے رہی ہے اور پھر آخرایسے
گروہ سے پناہ مانگنے کا حکم ہے جو شیطان کے زیر سایہ چلتا ہے.اس ترتیب سے صاف معلوم
ہوتا ہے کہ یہ وہی گروہ ہے جس کو دوسرے لفظوں میں شیطان کہا ہے.اور اخیر میں اس گروہ
کے ذکر سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آخری زمانہ میں اس گروہ کا غلبہ ہوگا جن کے ساتھ
تقلت في العقد ہوں گی.یعنی ایسی عیسائی عورتیں جو گھروں میں پھر کر کوشش کریں گی کہ
عورتوں کو خاوندوں سے علیحدہ کریں اور عقد نکاح کو توڑیں.خوب یاد رکھنا چاہئے کہ یہ تینوں سورتیں قرآن شریف کی دجالی زمانہ کی خبر دے رہی
ہیں اور حکم ہے کہ اس زمانہ سے خدا کی پناہ مانگو تا اس شر سے محفوظ رہو.یہ اس بات کی طرف
اشارہ ہے کہ وہ شرور صرف آسمانی انوار اور برکات سے دور ہوں گے جن کو آسمانی مسیح اپنے
1155
Page 1164
ساتھ لائے گا.(ماخوذ از ایام الصلح ، روحانی خزائن جلد 14 صفحہ 296 297)
اس سورہ میں تین قسم کے حق بیان فرمائے ہیں.اوّل فرما یا کہ تم پناہ مانگو اللہ کے پاس جو
جامع جمیع صفات کاملہ ہے.اور جو رب ہے لوگوں کا.اور ملک بھی ہے اور معبود ومطلوب حقیقی بھی
ہے.یہ سورہ اس قسم کی ہے کہ اس میں اصل توحید کو تو قائم رکھا ہے مگر مغایہ بھی اشارہ کیا ہے کہ
دوسرے لوگوں کے حقوق بھی ضائع نہ کریں جو ان اسماء کے مظہر ظلی طور پر ہیں.رب کے لفظ میں
اشارہ ہے کہ گوحقیقی طور پر خدا ہی پرورش کرنے والا اور تکمیل تک پہنچانے والا ہے لیکن عارضی اور
ظنی طور پر دو اور بھی وجود ہیں جور بوبیت کے مظہر ہیں.ایک جسمانی طور پر ڈ وسرار وحانی طور پر.جسمانی طور پر والدین ہیں اور روحانی طور پر مرشد اور بادی ہے.(ماخوذ از روئیداد جلسه دعا، روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 602_603)
خدا تعالیٰ نے تکمیل اخلاق فاضلہ کے لئے رَبّ النَّاس کے لفظ میں والدین اور مر شد
کی طرف ایماء فرمایا ہے تا کہ اس مجازی اور مشہود سلسلہ شکر گزاری سے حقیقی رب و بادی کی
شکر گزاری میں قدم اُٹھائیں.اسی راز کے حل کی یہ کلید ہے کہ اس سورہ شریفہ کو رب الناس
سے شروع فرمایا ہے.الہ الناس سے آغا ز نہیں کیا.چونکہ مرشد روحانی خدا تعالیٰ کے منشاء
کے موافق اس کی توفیق و ہدایت سے تربیت کرتا ہے اس لئے وہ بھی اسی میں شامل ہے.پھر دوسرا ٹکڑا اس میں مَلِكِ النّاس ہے یعنی تم پناہ مانگو خدا کے پاس جو تمہارا بادشاہ
ہے.یہ ایک اور اشارہ ہے تا لوگوں کو متمدن دنیا کے اصول سے واقف کیا جاوے اور مہذب
بنایا جاوے.حقیقی طور پر تو اللہ تعالی ہی بادشاہ ہے.مگر اس میں اشارہ ہے کہ ظنی طور پر بادشاہ
ہوتے ہیں اور اسی لئے اس میں اشارہ ملک وقت کے حقوق کی نگہداشت کی طرف بھی ایما
ہے.یہاں کافر اور مشرک اور موحد بادشاہ یعنی کسی قسم کی قید نہیں بلکہ عام طور پر ہے خواہ کسی
مذہب کا بادشاہ ہو، مذہب اور اعتقاد کے حصے جدا ہیں.قرآن میں جہاں جہاں خدا نے محسن
کا ذکر فرمایا ہے وہاں کوئی شرط نہیں لگائی کہ وہ مسلمان ہو اور موحد ہو اور فلاں سلسلہ کا ہو بلکہ
1156
Page 1165
عام طور پر محسن کی نسبت ذکر ہے.خواہ وہ کوئی مذہب رکھتا ہو اور پھر خدا تعالیٰ اپنے کلام پاک
میں محسن کے ساتھ احسان کرنے کی سخت تاکید فرماتا ہے جیسے آیت ذیل سے ہویدا ہے هَلْ جَزَاءُ
الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ (الرحمن : 61) کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا بھی ہوسکتا ہے.( ماخوذ از روئیداد جلسه دعا، روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 603_604)
حمد پہلے اس سورۃ میں خدا تعالیٰ نے رَبّ النّاس فرمایا پھر مَلِكِ النَّاسِ آخر میں الهِ
الناس فرما یا جو اصلی مقصود اور مطلوب انسان ہے.الہ کہتے ہیں معبود، مقصود، مطلوب کو.لا
إلهَ إِلَّا الله کے معنی یہی ہیں کہ لَا مَعْبُودَ لِي وَلَا مَقْصُودَ لِي وَلَا مَطْلُوبَ لِي إِلَّا اللهُ یہی سچی
توحید ہے کہ ہر مدح و ستائش کا مستحق اللہ تعالیٰ ہی کو ٹھہرایا جاوے.پھر فرمایا من شير
الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ یعنی وسوسہ ڈالنے والے خناس کے شر سے پناہ مانگو.خنّاس عربی میں سانپ کو کہتے ہیں جسے عبرانی میں نحاش کہتے ہیں اس لئے کہ اس نے
پہلے بھی بدی کی تھی.یہاں ابلیس یا شیطان نہیں فرمایا تا کہ انسان کو اپنی ابتدا کی ابتلا یاد آوے
کہ کس طرح شیطان نے اُن کے ابوین کو دھوکا دیا تھا اس وقت اس کا نام خناس ہی رکھا گیا
تھا یہ ترتیب خدا نے اس لئے اختیار فرمائی ہے تا کہ انسان کو پہلے واقعات پر آگاہ کرے کہ
جس طرح شیطان نے خدا کی اطاعت سے انسان کو فریب دے کرڑ وگرداں کیا ویسے ہی وہ کسی
وقت ملک وقت کی اطاعت سے بھی عاصی اور روگرداں نہ کرا دے.یوں انسان ہر وقت اپنے
نفس کے ارادوں اور منصوبوں کی جانچ پڑتال کرتا رہے کہ مجھ میں ملک وقت کی اطاعت کس
قدر ہے اور کوشش کرتا رہے اور خدا تعالیٰ سے دعا مانگتا رہے کہ کسی مدخل سے شیطان اُس
میں داخل نہ ہو جائے.اب اس سورۃ میں جو اطاعت کا حکم ہے وہ خدا تعالیٰ ہی کی اطاعت کا حکم
ہے کیونکہ اصلی اطاعت اُسی کی ہے مگر والدین ، مرشد و بادی اور بادشاہ وقت کی اطاعت کا حکم
بھی خدا ہی نے دیا ہے اور اطاعت کا فائدہ یہ ہوگا کہ خناس کے قابو سے بچ جاؤ گے.پس پناہ
مانگو کہ خناس کی وسوسہ اندازی کے شر سے محفوظ رہو.(ماخوذ از روئیداد جلسه، روحانی خزائن جلد 15 صفحه 619،618)
1157
Page 1166
کہو کہ تم یوں دُعا مانگا کرو کہ ہم وسوسہ انداز شیطان کے وسوسوں سے جولوگوں کے
دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے اور اُن کو دین سے برگشتہ کرنا چاہتا ہے کبھی بطور خود اور کبھی کسی انسان
میں ہوکر، خدا کی پناہ مانگتے ہیں.وہ خدا جو انسانوں کا پرورندہ ہے.انسانوں کا بادشاہ ہے.انسانوں کا خدا ہے.یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایک زمانہ آنے والا ہے جو اس میں نہ
ہمدردی انسانی رہے گی جو پرورش کی جڑ ہے.اور نہ سچا انصاف رہے گا جو بادشاہت کی شرط
ہے.تب اس زمانہ میں خدا ہی خدا ہو گا جو مصیبت زدوں کا مرجع ہوگا.یہ تمام کلمات آخری
زمانہ کی طرف اشارات ہیں جبکہ امان اور امانت دنیا پر سے اٹھ جائے گی.(تحفہ گولڑویہ، روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 222،221)
واضح ہو کہ خناس شیطان کے ناموں میں سے ایک نام ہے یعنی جب شیطان سانپ کی
سیرت پر قدم مارتا ہے اور کھلے کھلے اکراہ اور جبر سے کام نہیں لیتا اور سراسر مکر اور فریب اور
وسوسہ اندازی سے کام لیتا ہے اور اپنی نیش زنی کے لئے نہایت پوشیدہ راہ اختیار کرتا ہے تب
اُس کو خناس کہتے ہیں.عبرانی میں اس کا نام نحاش ہے.چنانچہ توریت کے ابتدا میں لکھا
ہے کہ نحاش نے حوا کو بہکایا اور حوا نے اس کے بہکانے سے وہ پھل کھایا جس کا کھانا منع کیا
گیا تھا.تب آدم نے بھی کھایا.سو اس سورۃ الناس سے واضح ہوتا ہے کہ یہی نحاش آخری زمانہ
میں پھر ظاہر ہوگا اسی معاش کا دوسرا نام دجال ہے.یہی تھا جو آج سے چھ ہزار برس پہلے
حضرت آدم کے ٹھو کر کھانے کا موجب ہوا تھا اور اس وقت یہ اپنے اس فریب میں کامیاب ہو
گیا تھا اور آدم مغلوب ہو گیا تھا لیکن خدا نے چاہا کہ اسی طرح چھٹے دن کے آخری حصے میں آدم
کو پھر پیدا کر کے یعنی آخر ہزار ششم میں جیسا کہ پہلے وہ چھٹے دن میں پیدا ہوا تھا معاش کے
مقابل پر اس کو کھڑا کرے اور اب کی دفعہ معاش مغلوب ہو اور آدم غالب.سو خدا نے آدم کی
مانند اس عاجز کو پیدا کیا اور اس عاجز کا نام آدم رکھا.جیسا کہ براہین احمدیہ میں یہ الہام ہے
ارَدْتُ أَنْ اسْتَخْلِفَ فَخَلَقْتُ آدَمَ - اور نیز یہ الہام خَلَقَ آدَمَ فَاكْرَمَهُ اور نیز یہ الہام کہ
يَا آدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ.اور آدم کی نسبت تو ریت کے پہلے باب میں یہ آیت ہے
1158
Page 1167
تب خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت اور اپنی مانند بناویں.دیکھو توریت باب اڈل
آیت 26.اور پھر کتاب دانی ایل باب نمبر 12 میں لکھا ہے اور اُس وقت میکائیل ( جس کا
ترجمہ ہے خدا کی مانند ) وہ بڑا سردار جو تیری قوم کے فرزندوں کی حمایت کے لئے کھڑا ہے
اُٹھے گا.( یعنی مسیح موعود آخری زمانہ میں ظاہر ہوگا ) پس میکائیل یعنی خدا کی مانند.در حقیقت
توریت میں آدم کا نام ہے اور حدیث نبوی میں بھی اسی کی طرف اشارہ ہے کہ خدا نے آدم کو
اپنی صورت پر پیدا کیا.پس اس سے معلوم ہوا کہ مسیح موعود آدم کے رنگ پر ظاہر ہوگا اسی وجہ
سے آخری ہزار ششم اس کے لئے خاص کیا گیا کیونکہ وہ بجائے روز ششم ہے یعنی جیسا کہ روز
ششم کے آخری حصے میں آدم پیدا ہوا اسی طرح ہزار ششم کے آخری حصہ میں مسیح موعود کا پیدا
ہونا مقدر کیا گیا.اور جیسا کہ آدم مخاش کے ساتھ آزمایا گیا جس کو عربی میں خناس کہتے ہیں
جس کا دوسرا نام دجال ہے ایسا ہی اس آخری آدم کے مقابل پر مخاش پیدا کیا گیا تا وہ
زن مزاج لوگوں کو حیات ابدی کی طمع دے جیسا کہ حوا کو اس سانپ نے دی تھی جس کا نام
توریت میں مخاش اور قرآن میں خناس ہے لیکن اب کی دفعہ مقدر کیا گیا کہ یہ آدم اُس مخاش
پر غالب آئے گا.غرض اب چھ ہزار برس کے اخیر پر آدم اور شخاش کا پھر مقابلہ آپڑا ہے اور اب وہ
پُرانا سانپ کاٹنے پر قدرت نہیں پائے گا جیسا کہ اول اُس نے حوا کو کاٹا اور پھر آدم نے اس زہر
سے حصہ لیا بلکہ وہ وقت آتا ہے کہ اس سانپ سے بچے کھیلیں گے اور وہ ضرررسانی پر قادر نہیں ہوگا.قرآن شریف میں یہ لطیف اشارہ ہے کہ اس نے سورہ فاتحہ کو الضالین پر ختم کیا اور قرآن کو خناس
پر.تا دانشمند انسان سمجھ سکے کہ حقیقت اور روحانیت میں یہ دونوں نام ایک ہی ہیں.(تحفہ گولڑو یہ ، روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 272 تا 275 حاشیہ)
قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاس میں شیطان کے ان وساوس کا ذکر ہے جو کہ وہ لوگوں کے درمیان
ان دنوں ڈال رہا ہے.بڑا وسوسہ یہ ہے کہ ربوبیت کے متعلق غلطیاں ڈالی جائیں جیسا کہ امیر لوگوں
کے پاس بہت مال و دولت دیکھ کر انسان کہے کہ یہی پرورش کرنے والے ہیں.اس واسطے حقیقی رب الناس کی پناہ چاہنے کے واسطے فرمایا پھر دنیوی بادشاہوں اور
1159
Page 1168
حاکموں کو انسان مختار مطلق کہنے لگ جاتا ہے.اس پر فرمایا کہ مَلِكِ الناس اللہ ہی ہے.پھر لوگوں کے وساوس کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ مخلوق کو خدا کے برابر ماننے لگ پڑتے ہیں اور ان
سے خوف و رجا ر کھتے ہیں اس واسطے الہ الناس فرمایا.یہ تین وساوس ہیں ان کے دُور کرنے
کے واسطے یہ تین تعویذ ہیں.الحکم جلد 5 نمبر 12 مورخہ 31 مارچ1901 ، صفحہ 10)
حضرت خلیفہ المسح الاول رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:
حمد اس سورہ شریفہ میں اللہ تعالیٰ کی تین صفتوں کا بیان کیا گیا ہے.ربّ مالك اله اور
پھر ان ہر سہ صفات کے اُس پر تو کی طرف بالخصوص اشارہ کیا گیا ہے جو کہ انسان کے ساتھ
تعلق رکھتا ہے....وہ جو ہمارا رب ہے اور جو ہمارا ملک ہے اور سلطان ہے.وہی اس لائق
ہے کہ ہمارا الہ ہو اور معبود ہو، اسی کی عبادت کی جاوے، اسی سے اپنی حاجتیں مانگنی چاہئیں.اور اسی کی تعریف کرتے ہوئے سر اس کے آگے جھکا یا جاوے.اس دعا میں انسان اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہو کر اپنے خدا کے ساتھ اس تعلق کو یاد
کرتا ہے کہ اے خدا تو ہی میرا پرورش کنندہ ہے اور تو ہی میرا بادشاہ ہے اور تو ہی میرا معبود
ہے.پس میں تیرے ہی حضور میں اپنی یہ درخواست پیش کرتا ہوں کہ نیکی کے حصول کے بعد جو
انسان کے دل میں ایسے بُرے خیالات آتے ہیں کہ اس کو نیکی سے پیچھے ہٹانا چاہتے ہیں ان
خیالات کے شر سے مجھے بچا.اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ وسوسوں کا پیدا ہونا ضروری ہے.پر جب تک انسان ان
کے شر سے بچا ر ہے یعنی ان کو اپنے دل میں جگہ نہ دے اور ان پر قائم نہ ہوتب تک کوئی حرج
نہیں.ایک دفعہ ایک شخص نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کی
کہ میرے دل میں بُرے برے خیالات پیدا ہوتے ہیں.کیا میں ان کے سبب سے گنہگار
ہوں؟ فرمایا فقط بُرے خیال کا اٹھنا اور گزر جانا تم کو گنہگار نہیں کرتا ، یہ شیطان کا ایک وسوسہ ہے
1160
Page 1169
جیسا کہ بعض انسان جو شیطان کی طرح ہوتے ہیں ، لوگوں کے دلوں میں بُرے خیالات ڈالنے
کی کوشش کرتے ہیں.پس فقط اُن کی بات سننے سے اور ر ڈ کر دینے سے کوئی گنہگار نہیں ہو
سکتا.ہاں وہ گنہگار ہوتا ہے جو ان کی بات کو مان لیتا اور اس پر عمل کر لیتا ہے.سورۃ الناس قرآن شریف کی سب سے آخری سورۃ ہے اور اس کا مضمون آخری زمانہ میں
ایک بڑے فتنہ سے خدا تعالی کی پناہ مانگنے کا حکم دیتا ہے.وہ فتنہ خناس کا ہے جو کہ لوگوں کے دلوں
میں قسم قسم کے وساوس ڈال کر ان کو پیچھے ہٹانے کی کوشش کرے گا.اس سورت سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ آخری زمانہ جنگ کا زمانہ ہوگا.اور اسلام سے
لوگوں کی رُوگردانی کرانے کے واسطے کوئی لڑائی اور ظاہری جنگ کی کارروائی نہ ہوگی.جیسا کہ
کیا جاتا تھا.بلکہ صُدُورِ النّاس پر بذریعہ وساوس ہوگا.اور وہ وسوسہ ڈالنے والے
خناس دو قسم کے ہوں گے.ایک تو پادری لوگ جن کے وساوس موٹے رنگ کے ہر طرح کے
کذب اور بہتان کے ساتھ ہیں.یہ خناس تو ناس میں سے ہے.لیکن ایک بڑا خناس جوشئر میں اس سے زیادہ سخت ہے.لیکن اپنی شرارت میں کسی قدر مخفی ہے
اس واسطے اس کو جن کہا گیا ہے وہ اس زمانہ کے جھوٹے فلسفی اور جزوی سائنس دان ہیں جو حقیقی
فلسفہ اور سائنس سے بے خبر ہیں اور تعلیم یافتہ گروہ کو خفیہ رنگ میں دہریت کی طرف کھینچ کر لے جا
رہے ہیں.حالانکہ بظاہر مذہب سے اپنے آپ کو بے تعلق ظاہر کرتے ہیں.مگر باطن میں مذہب
کے سچے اصول کو اکھاڑنے کے درپے ہیں.اس سورۃ شریفہ میں یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ آخری زمانہ کا فتنہ محض دعا کے ذریعہ سے
ڈور ہوگا.چنانچہ اس کی تائید میں حدیث شریف میں آیا ہے کہ کفار مسیح موعود کے دم سے مریں
گے.اور حضرت مرزا صاحب سے میں نے بار ہا سنا ہے.آپ فرمایا کرتے ہیں کہ اس قد رفتنہ
کامٹانا ظاہری اسباب کے ذریعہ سے نہیں ہو سکتا.ہمارا بھروسہ صرف ان دعاؤں پر ہے جو کہ ہم
اللہ تعالیٰ کے حضور میں کرتے ہیں.خداوند تعالیٰ ہماری دعاؤں کو سنے گا اور وہ خود ہی ایسے سامان
1161
Page 1170
مہیا کرے گا کہ کفر ذلیل ہو جائے گا اور اسلام کے واسطے غلبہ اور عزت کے دن آجائیں گے.یہ ایک عجیب دعا ہے جو خدا تعالیٰ نے خود ہم کو سکھائی ہے.اس کے کسی قدر ہم معنے وہ
دعا ہے جو دوسری جگہ قرآن شریف میں آتی ہے اور وہ اس طرح ہے.رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا
بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا (آل عمران (9) اے ہمارے رب بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت کی توفیق
عطا فرمائی.ہمارے دلوں کو کج نہ کر.یعنی ایک دفعہ جس نیکی کو ہم حاصل کریں وہ استقامت
کے ساتھ ہمارے اندر قائم رہے.حمل یہ سورۃ شریفہ قرآن شریف میں سب سے آخری دعا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ یہ قرآن جس
کے پڑھنے کی تو نے ہم کو توفیق دی ہے.اب ایسا کر کہ ہمارے دل اس پر ایمان کے واسطے
ایسے پختہ رہیں کہ اس کلام کے متعلق کوئی وسوسہ اور بدخیال کبھی ہمارے دل میں نہ آنے
پاوے.اور ہم اس پر عمل کریں اور تیرے نیک بندوں میں شامل ہو جاویں.قرآن شریف کے
ذریعہ سے رحمان خدا نے کس قدر رحمت دنیا پر نازل فرمائی.تمام احکام شرعیہ، گزشتہ بزرگوں
کی نیک مثالیں، طریق دعا ، غرض ہر شئے ضروری کی تعلیم دی گئی ہے.میں خیال کرتا ہوں کہ امراض سینہ مثلاً سل، کھانسی وغیرہ کے واسطے اس سورہ شریفہ
میں ایک دعا ہے.کیونکہ آجکل ڈاکٹروں نے یہ تحقیقات کی ہے کہ پھیپھڑے میں ایک
باریک کیڑے ہوتے ہیں جن کو جرمز (germs) کہتے ہیں.جب وہ پیدا ہو جاتے ہیں تب
پھیپھڑا زخمی ہو کر رسل کی بیماری اور کھانسی پیدا ہو جاتی ہے.جن بھی ایک بار یک اور مخفی شئے کو
کہتے ہیں.اس سورۃ میں ان اشیاء کے شر سے پناہ چاہی گئی ہے جو سینہ کے اندر ایک خرابی پیدا
کرتے ہیں.ناظرین اس کا تجربہ کریں.لیکن صرف جنتر منتر کی طرح ایک دعا کا پڑھنا اور
پھونک دینا بے فائدہ ہے.سچے دل کے ساتھ اور معنی کو یہ سورۃ بطور دعا کے مریض اور اس
کے معالج اور تیماردار پڑھیں اور مریض کے حق میں دعا کریں تو اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے اور بخشنے
والا ہے.میں امید کرتا ہوں کہ ایسے بیماروں کو اس کلام پاک کے ذریعہ شفا حاصل ہو.واللہ
اعلم بالصواب.1162
Page 1171
حمد اس سورہ شریفہ کے شان نزول کے بارہ میں حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آج کی رات مجھ پر اس قسم کی آیات نازل ہوئیں کہ ان جیسی
میں نے کبھی نہیں دیکھیں وہ معوذتین ہیں.ابوسعید خدری کہتے ہیں کہ رسولِ خدا صلی اللہ
علیہ وسلم جن و انس کی نظر بد سے پناہ مانگا کرتے تھے ،مگر جب مُعوذتین نازل ہوئیں تو آپ
نے اور طرح اس امر کے متعلق دعا کرنا چھوڑ دیا اور ہمیشہ ان الفاظ میں دعا مانگتے تھے.حضرت
عائشہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوا کرتے تو ان دونوں سورتوں کو پڑھ
پڑھ کر دم کیا کرتے تھے.ضمیمه اخبار بدر قادیان 9 جنوری 1912ء)
یہ قرآن کی آخری سورۃ کیسی بے نظیر اور لطیف ہے جس میں یہ بیان ہے کہ تم اللہ کریم ،
المولى، الرؤوف الرحيم ، ربّ الناس، ملک الناس ، الہ الناس سے پناہ مانگ لو تمام ان غلطیوں
اور وسوسوں سے جو کسی مؤسوس کے نظارہ یا کلام سے بندہ کو ہوں کیونکہ ان وسوسوں کی مثال ہو
بہو اس تکلیف رساں گنے کی سی ہے جو آٹھوں پہر کاٹنے کے لئے تیار ہے.جس طرح اس گئے
سے بچنے کے لئے ہم کو اس کے مالک کی پناہ مانگنی ہے اور اگر اس کا مالک ہمیں بچانا چاہے
اور اس گتے کو دھتکار دے تو کیا مجال کہ وہ کتا کسی کو کاٹ کھائے.اسی طرح انسانی یا شیطانی
وسوسوں سے بچنا بھی اس وجود کی پناہ سے ہو گا جو گل مخلوقات کا رب اور مالک اور محبوب ہے.وَسُو اس نام ہے ہر ایک ایسی چیز کا جس کا بُرا ہونا ہم سے مخفی رہ گیا اور جس کی بدی
سے ہم بے خبر رہے اور اس کی شرارت ہمارے جسم پر یا اخلاق پر یا روحانی معاملات پر اثر
ڈالتی ہو یا ڈالا ہو اور ہمیں اس کی اطلاع نہ ملی ہو.چاہے وہ مخفی چیز ہو.چاہے وہ انسان، ہاں
شیطان بصورت انسان سے.( رپورٹ جلسہ اعظم مذاہب صفحہ 258 تا261)
حم...اس سورۃ کو آخیر میں لانے میں یہ حکمت ہے کہ قرآن کو ختم کر کے اور شروع
1163
Page 1172
کرتے ہوئے اَعُوذُ پڑھنا چاہئے.چونکہ یہ طریق مسنون ہے کہ قرآن کریم ختم کرتے ہی
شروع کر دینا چاہئے، اس لئے نہایت عمدہ موقعہ پر یہ سورۃ ہے.ماخوذ از حقائق الفرقان زیر تفسیر سورۃ الناس )
حضرت خلیفہ المسیح الثانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:
بدر مورخہ 22 جولائی 1909 صفحہ 2)
سورۃ فاتحہ کا مضمون قرآن کریم کی آخری تین سورتوں میں دہرادیا گیا ہے.گویا جس
بنیاد پر قرآن کریم کو شروع کیا گیا تھا اسی پر آکر ختم کیا گیا ہے.اس سورۃ کا دوسرا تعلق سورۃ لہب سے ہے.سورۃ لہب میں ایک دشمن اسلام کے پیدا
ہونے اور اس کے انجام کا ذکر تھا.اس سورۃ میں اس دشمن کے متعلق بعض تفصیلات کا ذکر کیا
گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ وہ کن کن ذرائع سے اسلام پر حملہ آور ہوگا.اس سورۃ کا تیسرا تعلق سورۃ الفلق کی آخری آیت سے بھی ہے.سورۃ الفلق کی آخری
آیت وَ مِنْ شَرِ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ میں یہ بتایا گیا تھا کہ ایک عظیم الشان حاسد مسلمانوں کا پیدا
ہونے والا ہے اور یہ کہ مسلمانوں کو اس کے شر سے بچنے کے لئے دعا کرتے رہنا چاہئے.سورۃ
الناس میں اس حاسد کے متعلق بتایا کہ وہ عیسائی قوم ہے.اور وہ اس اس طرح اسلام پر حملہ
کرے گی.سورۃ لہب...میں ایک ایسی قوم کے خروج کا ذکر ہے.جس نے آخری زمانہ میں
اسلام پر حملہ کرنا تھا.اور یہ کوشش کرنی تھی کہ محمد رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کالا یا ہوا دین ختم
ہو جائے.سورۃ الفلق کی آخری آیت وَ مِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ میں بھی اسی قوم کے حملوں
سے بچنے کی دعا امت محمدیہ کو سکھائی گئی تھی.اور بتایا تھا کہ آخری زمانہ میں ایک طاقتور حاسد
پیدا ہو گا جو اس بات کا متمنی ہو گا کہ نہ صرف یہ کہ وہ اسلامی حکومتوں کو ختم کر کے اسلامی ممالک
1164
Page 1173
پر قبضہ کرلے.بلکہ اس کی یہ خواہش بھی ہوگی کہ اسلام کا نام لینے والا اس دنیا میں کوئی باقی نہ
رہے.چونکہ اس قوم کو مادی طور پر ہر قسم کی طاقتیں حاصل ہونی تھیں اور مسلمان بوجہ ضعف و
کمزوری کے اس قوم کا مقابلہ کرنے سے عاجز رہنے تھے.اس لئے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو
دعا سکھائی کہ اس خطرناک فتنہ سے بچنے کے لئے اللہ تعالی کی پناہ طلب کرو تا وہ ایسے اسباب
پیدا کر دے کہ اسلام نہ صرف اس دشمن کے حملوں سے محفوظ رہے بلکہ ضعف کے بعد اس پر پھر
اس کی شان و شوکت کے دن آجائیں.سورۃ الناس کے ابتداء میں اللہ تعالی کی تین صفات کا ذکر کیا گیا ہے اور کہا گیا
ہے کہ ان کے ذریعہ سے پناہ مانگو.چنانچہ فرما یا قُل اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلهِ
الناس.یعنی یہ کہو کہ اے خدا جو رب ہے لوگوں کا ہم تیری پناہ مانگتے ہیں.اے خدا جو بادشاہ
ہے سب کا.ہم تیری پناہ مانگتے ہیں.اے خدا جو معبود ہے سب
کا ہم تیری پناہ مانگتے ہیں اور
یہ ظاہر بات ہے کہ جس چیز کی طرف نسبت دیکر پناہ مانگی جاتی ہے.دراصل اسی چیز سے پناہ
پانا مقصود ہوتا ہے.مثلاً جب ہم کہتے ہیں اے گئے والے ہمیں بچا.تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کہہ
رہے ہیں کہ ہمیں کتنے سے بچا.یا اگر ہم کسی ایسی جگہ جاتے ہیں جہاں کسی نے شیر پال رکھا ہو
اور کہیں اے شیر والے دوڑ یو! تو معلوم ہوتا ہوگا کہ شیر سے بچنے کے لئے کہہ رہے ہیں.پس
جب ہم رَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ الهِ النَّاسِ کی پناہ مانگتے ہیں تو معلوم ہوا کہ ہم ناس کی
ان خصوصیتوں سے پناہ مانگتے ہیں جن کا تعلق ربوبیت سے ہے یا ان خصوصیتوں سے پناہ
مانگتے ہیں جن کا تعلق ملکیت سے ہے.یا ان خصوصیتوں سے پناہ مانگتا ہوں جن کا تعلق
اُلوہیت سے ہے.ناس کی ربوبیت ڈیما کریسی کے ذریعہ سے ظاہر ہوتی ہے اور اس میں بھی
بعض خرابیاں ہوتی ہیں اور.ناس کی ملوکیت اقتدار سے ظاہر ہوتی ہے جو کسی قوم کو دوسرے
ملکوں پر ہوتا ہے.اور اس سے بھی کچھ خرابیاں ہوتی ہیں.اور ناس کی الوہیت اس عام غیر
مذہبی رو سے ظاہر ہوتی ہے جو کسی لا مذہب قوم میں پیدا ہو جاتی ہے اور جس کی وجہ سے اس
1165
Page 1174
سے کم ترقی یافتہ ملکوں میں بھی لامذہبیت کی رو پھیل جاتی ہے.سورۃ الناس میں سارا نقشہ مغربی اقوام کا کھینچا گیا ہے اور یہی وہ حاسد قوم ہے جس کو
مسلمانوں کی طاقت دیکھنا گوارا نہیں.اور وہ چاہتی ہے کہ اسلام کا نام دنیا سے مٹ جائے.پس اس قوم کے پیدا کردہ فتنوں سے بچنے کے لئے مسلمانوں کو دعا سکھائی گئی ہے اور دعا کے
پہلے الفاظ یہ ہیں کہ میں رب الناس کی پناہ چاہتا ہوں.صفت ربوبیت کے ماتحت تمام وہ
چیزیں آتی ہیں جو انسانی ضروریات کہلاتی ہیں اور جن کو ملک کی اقتصادیات کے نام سے پکارا
جاتا ہے.گویا قُل اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاس میں یہ اشارہ ہے کہ جب مسلمانوں کا حسد نکلے گا تو سب
سے پہلے ان کی اقتصادیات کو تباہ کرے گا اور تجارت کو نقصان پہنچائے گا....پس اللہ تعالیٰ نے اُن کے اس فتنے سے محفوظ رہنے کے لئے قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ کے
الفاظ سکھائے اور بتایا کہ اگر اُن کے شر سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ تعالی کی پناہ میں آنا.رب الناس کے بعد مَلِكِ النّاس کے الفاظ سکھائے.گویا اس میں یہ اشارہ کیا کہ مغربی
اقوام کے اقتصادی فتنہ کے بعد ملوکیت کا فتنہ شروع ہوگا....ملِكِ النّاس کے بعد الہ الناس کے الفاظ رکھے گئے ہیں.اور اس میں یہ بتانا مقصود
ہے کہ جب مغربی اقوام مختلف ممالک میں بادشاہتیں قائم کرلیں گی تو ان کی طرف سے ایک
اور فتنہ برپا ہوگا.یعنی مذہبی پروپیگنڈ ا شروع کر دیں گی اور اس طرح مسلمانوں کا ایمان متزلزل
کردیں گی اور نیا فلسفہ اور نئی تعلیم پیش کر کے مذہب کو برباد کرنے کی کوشش کریں گی.کا لجوں وغیرہ میں تعلیم کے ذریعہ مسلمانوں کے مذہبی عقائد کو کھوکھلا کر دیں گی.اور اس قسم کا
لٹریچر شائع کریں گی جس سے مذہب اسلام ایک غیر معقول مذہب نظر آئے اور لوگ اس
سے متنفر ہوں.پس فرمایا.اے مسلمانو! جب تمہیں ان حالات سے دو چار ہونا پڑے.تو تم اس خدا کی پناہ
چا ہو.جو رب، مالك اور الہ ہے.یعنی یہ دعا کرو کہ اے خدا صحیح ربوبیت، صحیح ملوکیت اور صحیح
1166
Page 1175
الوہیت جس کو تو دنیا میں رائج کرنا چاہتا اور پھیلانا چاہتا ہے اس کو ختم کیا جارہا ہے.پس تو ایسا
انتظام فرما کہ یہ فتنے مٹ جائیں اور پھر تیری صحیح ربوبیت صحیح مالکیت اور صحیح الوہیت دنیا پر
قائم ہو جائے.قُل اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ الهِ النّاس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر
حکومتیں تمہیں ڈرائیں، تمہاری بات نہ سنیں، تم پر ظلم کریں، تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں تو تم
میرے دربار میں آؤ.میں تمہارا اصل بادشاہ ہوں.اگر ملک یا قوم یا خاندان کی طرف سے تم پر
ظلم کیا جاتا ہے تو تم میرے دربار میں آؤ.میں تمہارا رب ہوں اور تمہارا خاندان اور تمہاری قوم
بھی میرے قبضہ میں ہے.اگر مذہبی پیشوا تمہیں گمراہ کرنا چاہیں تو تم میرے دربار میں آؤ کیونکہ
میں تمہارا اللہ ہوں اور تمہاری ہدایت میرے ذمہ ہے.اور اگر تم میرے پاس آؤ گے تو تمہیں
کوئی نقصان نہیں پہنچ سکے گا.نہ ربوبیت کی قسم کا.نہ ملکیت کی قسم کا.نہ الوہیت کی قسم کا....الغرض آخری زمانہ میں ربوبیت ، ملوکیت اور الوہیت کے ماتحت جو فتنے مخالفین اسلام
کی طرف سے اٹھنے والے تھے.اُن کے لئے اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ
میں ایک جامع دعا امت محمدیہ کو سکھا دی گئی ہے.مِن شَرًا لُوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ
والناس کے معنے ہیں.میں اس وسوسہ اندازی کرنے والے کے شر سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں
جو وسوسہ ڈال کر پیچھے ہٹ جاتا ہے یا پوشیدہ رہ کر چھوٹے اور بڑے لوگوں کے دلوں میں وسوسہ
پیدا کرتا ہے.کئی شرارت کرنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ شرارت کرنے کے بعد سامنے کھڑے
رہتے ہیں.مگر کئی شرارت کر کے ایسے مخفی ہو جاتے ہیں کہ ان
کا پتہ بھی نہیں چلتا اور بعض پوشیدہ
کارروائیاں کرتے رہتے ہیں.مغربی اقوام کا یہ خاصہ ہے کہ وہ سیاسیات اور دوسرے امور میں
ہمیشہ ایسا طرز عمل اختیار کرتے ہیں کہ جس کا دوسروں
کو علم بھی نہیں ہوتا اور دوسرا ملک تباہ ہو جاتا
1167
Page 1176
ہے.اسی طرح مختلف کتابیں لکھتے ہیں اور ظاہر یہ کرتے ہیں کہ ہم علم پھیلا رہے ہیں لیکن یا تو
اسلام سے نفرت پھیلاتے ہیں اور یا دہریت.گویا اس طرح سے اپنے ملکوں میں بیٹھے دوسروں
کو تباہ کرتے ہیں.وسواس کے ایک معنے صَوْتُ الْحَل کے بھی ہیں.یعنی اس آواز کے جو زیوروں کی
جھنکار سے پیدا ہوتی ہے.اس لحاظ سے مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ کے یہ معنے ہیں کہ
آخری زمانہ میں مغربی اقوام روپیہ کی لالچیں اور حرص ولا دلا کر لوگوں کو گمراہ کریں گی.اور پھر
ساتھ ہی وہ خناس بھی ہوں گی یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ کھلے بندوں دس ہزار روپیہ کسی کو اپنی
ذاتی اغراض کے لئے دیں.بلکہ وہ اس طرح دیں گی کہ رو پی بھی دوسرے کو پہنچ جائے اور خود
بھی چھپی بیٹھی رہیں.ایسے حالات میں ہر مومن کو یہ دعا کرنی چاہئے کہ الہی تو مجھے ان کے فتنہ
اور شر سے بچا.پھر يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاس میں بتایا کہ یہ اقوام بعض دفعہ
بڑے آدمیوں کے ذریعہ اور بعض دفعہ عوام الناس کے ذریعہ میرے دل میں روپیہ کی محبت پیدا
کریں گی.یا یہ اقوام اتنی دولتمند ہوں گی کہ اگر میں بڑا ہو جاؤں تب بھی یہ مجھے لالچ دے سکیں
گی اور اگر میں عوام میں شامل رہوں تب بھی مجھے لالچ دے سکیں گی.ان آیات میں یہ پیشگوئی بھی ہے کہ آخری زمانہ میں جو فتنے برپا ہوں گے اُن میں
آرگنائزیشن ہوگی.یعنی ایک انتظام کے ماتحت یہ فساد ہوں گے.لوگ فردا فردا اس میں
حصہ نہیں لیں گے بلکہ دوسروں کو بھی اُکسائیں گے اور اپنے ساتھ ملائیں گے....اسی طرح
حکمر ان لوگوں کی علیحدہ تنظیم ہوگی اور ماتحتوں کی الگ اور ہر تنظیم دوسرے ملک کی تنظیم کے
ساتھ تعلق رکھے گی.اسی طرح مذہب کے خلاف جو فتنے ہوں گے وہاں بھی انجمنیں ہوں گی.مثلاً یہ نہیں کہ کوئی دہر یہ ہو تو اپنے آپ کو ظاہر نہ کرے.بلکہ ان کی بھی انجمنیں ہوں گی اور وہ
علی الاعلان کہیں گے کہ خدا کا غلط عقیدہ لوگوں کے دلوں سے مٹانا ہمارا کام ہے.1168
Page 1177
سورۃ الناس قرآن کریم کی آخری سورۃ ہے اور جب انسان سارا قرآن کریم پڑھ لیتا
ہے تو اس کے دل میں گھمنڈ پیدا ہوسکتا ہے کہ اب تو میں نے سارا قرآن پڑھ لیا اور اب میں
شیطان سے محفوظ ہو گیا ہوں اور کوئی ٹھو کر نہیں کھا سکتا.اس قسم کے خیالات چونکہ تباہ کرنے کا
موجب ہو سکتے ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے آخر میں فرمایا کہ اے بندے جسے
اب قرآن کریم پڑھنا اور اسے ختم کرنا نصیب ہوا ہے تو یہ نہ سمجھ کہ تو شیطان کے پنجہ سے محفوظ
ہو گیا ہے.بالکل ممکن ہے کہ رب العالمین خدا کو دیکھ کر اور اس کی اس صفت کا اپنے آپ کو
مورد پا کر تو ٹھو کر کھا جائے.خدا کے فضل ہر انسان پر ہر گھڑی نازل ہورہے ہیں.ایسا نہ ہو کہ
جب قرآن پڑھ کر خدا کے فضلوں کی طرف تیری توجہ ہو اور اس وقت خدا کی ربوبیت تیرے
لئے ظاہر ہو تو تو گھمنڈ میں آ جائے.اور اس طرح ٹھوکر کھا جائے.یاد رکھو کہ خدا رب الناس
ہے.اس کے فیوض معمولی سے معمولی انسان پر بھی ہورہے ہیں.تجھ پر اگر کوئی فضل نازل
ہوتا ہے تو اس وجہ سے کوئی گھمنڈ نہ کر اور ٹھو کر نہ کھا.بلکہ سمجھو کہ جب تیرے دل میں خدا کی
برکت اور فیوض حاصل کرنے کی تڑپ پیدا ہوئی تو خدا نے اپنی صفت ربوبیت کے ماتحت تجھ
پر کچھ نازل کر دیا.ہو سکتا ہے کہ اس وقت تک تیرے اندر پوری پاکیزگی نہ پیدا ہوئی ہو.پس
مجھے دعا کرنی چاہئے کہ میں اس خدا سے پناہ مانگتا ہوں جو سب کا رب ہے.اور کہتا ہوں اے
خدا جب تو میری حالت ناقص ہونے کی وجہ سے مجھ پر ناقص نعمتیں نازل کرتا ہے.اور اس طرح
ہمیشہ کے لئے نیک انجام ہونا مشکل ہے.اس لئے میں تجھ سے ہی التجا کرتا ہوں کہ تو مجھ پر
حقیقی رحمتیں نازل
فرما اور ہر قسم کی ٹھوکروں سے بچا.(ماخوذ از تفسیر کبیر زیر تفسیر سورة الناس)
حضرت خلیفہ اسی الثانی رضی اللہ عنہ خطبہ جمعہ فرمودہ 26 ستمبر 1916 میں فرماتے ہیں:
کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر محبت کا سلوک کرتے ہیں لیکن چونکہ ان کا تعلق
ملائکہ سے نہیں ہوتا اس لئے بجائے اس کے کہ کسی کو اوپر لے جانے میں مدد دیں.اور نیچے
1169
Page 1178
گرادیتے ہیں.ان کو انسان دوست سمجھتا ہے لیکن دراصل وہ اس کے دشمن ہوتے ہیں.فرمایا
ان سے بچنے کی ہم...ایک ترکیب بتاتے ہیں اور وہ یہ کہ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ.خدا سے
ہمیشہ ان سے محفوظ رہنے کی دعا مانگو.اس کو کہو کہ اے خدا! تو رب ہے.رب کے معنے ہیں
پیدا کرنے والا اور پیدا کرنے کے بعد اس کی بار یک در بار یک ضروریات کو پورا کر کے
کمال تک پہنچانے والا.تو فرمایا تم ایسے خدا سے مدد مانگو جورب ہے اور اسے کہو کہ ہمیں اس
سے بڑھ کر اور کیا ضرورت ہوگی کہ ہمیں ایسی خواہشات اور ایسے لوگوں سے تعلق نہ ہو جو ہمیں
نیچے ہی نیچے لے جانے والے ہوں.پس ہم اپنے آپ کو تیرے ہی سپرد کرتے ہیں کہ تو ہمیں
او پر لے جا.یہ توربوبیت کا واسطہ دے کر دعا ہوئی.اس سے بڑھ کر مالکیت کا درجہ ہے.فرمایا پھر اس خدا کو پکارو جو مَلِكِ النَّاس ہے.لوگوں
کا بادشاہ ہے.بادشاہ کبھی یہ پسند
نہیں کرتا کہ کوئی باغی اس کی رعایا کو تکلیف پہنچائے.اس لئے فرمایا خدا کو ملک کے نام
سے اپنی مدد کے لئے پکارو کہ اے خدا ہم تیری رعایا ہیں.کیا اگر ہمیں کوئی دکھ دے، کوئی
تکلیف پہنچائے تو تیری شان بادشاہت کو غیرت نہیں آئے گی.ضرور آئے گی.پس ہم کو بچا.دیکھو دنیاوی بادشاہوں کی رعایا کو اگر کوئی بہکائے تو انہیں غیرت آتی ہے اور وہ اسے بلاک اور
تباہ کر دیتے ہیں.اسی طرح اگر کوئی خدا تعالیٰ کو اپنا آپ سپر د کر دے تو کیا وہ اس کے بہکانے
والوں کوسز انہیں دے گا؟ ضرور دے گا.پس فرمایا کہ تم اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دو اور کہو کہ
الہی! تو ہی ہمارا بادشاہ ہے اور ہم تیری رعایا.ہمیں ان باغیوں اور سرکشوں سے نجات دے جو
تیرے جادۂ اطاعت سے ہمیں منحرف کرنا چاہتے ہیں.ربوبیت سے بڑھ کر اُلوہیت کا تعلق ہے.ہر ایک بادشاہ اللہ نہیں ہوسکتا.ایک ہی بادشاہ ایسا
ہے جو اللہ ہے.اور وہ خدا تعالیٰ ہے.فرمایا.اله الناس.پھر الوہیت کی صفت کو پکارو.اور کہو
خدایا! ہم تیرے بندے ہیں اور تو ہمارا معبود.جب کوئی بادشاہ یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کی رعایا کو کوئی
ورغلائے تو پھر تو جو معبود ہے کس طرح پسند کر سکتا ہے کہ تیرے بندوں کو کوئی ورغلائے.پس ہم
1170
Page 1179
تیرے ہی حضور عرض کرتے ہیں کہ تو ہمیں فسادوں اور فتنوں سے بچا.شریروں اور باغیوں کے
وساوس سے نجات دے اور بلند سے بلند درجے حاصل کرنے کی توفیق بخش.جس طرح بلندی کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ مشکلات بھی بڑھتی جاتی ہیں اسی طرح خدا تعالیٰ
نے اپنی صفات بھی علی الترتیب اعلی بیان فرما دی ہیں تا کہ جہاں مشکلات بڑھتی جائیں وہاں
خدا تعالیٰ کو اس کی اعلیٰ صفات کے مطابق اپنی مدد اور تائید کے لئے پکارتے جاؤ.اس زمانہ میں اس سورۃ کے پڑھنے کی بڑی ضرورت ہے.لوگوں کو آجکل دین سے بڑی
نفرت ہوگئی ہے.بعض جگہ بہت چھوٹی چھوٹی اور معمولی باتوں سے ابتلا آجاتے ہیں.مثلاً کسی
کا جنازہ نہیں پڑھا.یا کسی نے رشتہ نہیں دیا.یا فلاں کیوں سیکرٹری بنایا گیا.اور فلاں
پریذیڈنٹ کیوں بنایا گیا.مجھے حیرت ہی آتی ہے کہ اس زمانہ میں ایمان کی قیمت کیوں اس
قدر تھوڑی ہو گئی ہے.حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے لکھا ہے کہ اس زمانہ سے اس سورۃ کا
بہت تعلق ہے.چنانچہ تجربہ بتا تا ہے کہ واقعہ میں ہمارے دوستوں کو اس کی بہت ضرورت
ہے تاوہ شریر لوگ جو اُن کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں ان سے محفوظ رہیں.خناس و ہی ہستیاں ہوتی ہیں جو نظر نہیں آتیں یعنی پوشیدہ رہتی ہیں.کبھی کسی لباس میں اور
کبھی کسی لباس میں آکر وسو سے ڈالتی رہتی ہیں اور انسان
سمجھتا ہے کہ یہ میری خیر خواہ اور ہمدرد
ہیں.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ انسان رات کو
مومن سوئے گا اور صبح کو کا فراٹھے گا اور اسے پتہ بھی نہیں ہو گا کہ کس طرح اس کا ایمان چلا گیا.وہ یہی زمانہ ہے.اس میں لالچ، حسد، بغض، ناجائز رعب، خوف اتنا ترقی کر گیا ہے کہ ایمان
کی کچھ بھی قیمت نہیں رہی اور وہ اس طرح بیچ دیا جاتا ہے کہ گویا بہت ہی حقیر چیز ہے جس قدر
جلدی اپنے پاس سے دور ہو اتنا ہی اچھا ہے.اپنے گندوں اور میلوں کو لوگ اتنا جلدی نہیں
پھینکتے جتنا ایمان کو پھینکتے ہیں.اگر ان کو کہا جائے کہ رسم ورواج کے گندوں کو چھوڑ دو تولڑنے
پر تیار ہو جاتے ہیں کہ اس طرح ہماری ناک کٹ جاتی ہے مگر ایمان کو ترک کرنے کے لئے
1171
Page 1180
اگر کوئی کہے تو بڑی خوشی سے تیار ہو جاتے ہیں.تو یہ زمانہ اس سورۃ کے پڑھنے کا بہت مستحق
ہے تا کہ خدا تعالیٰ کی ربوبیت، مالکیت اور الوہیت کی صفات مدد کریں اور نیچے گرنے والی
ہستیوں میں سٹیم بھر جائے تاکہ وہ اوپر چڑھ سکیں.یہ خدا تعالیٰ کی مدد کے سوا ہو نہیں سکتا.اس
میں شک نہیں کہ کامیابی کے لئے اسباب کا ہونا بھی ضروری ہے.مگر جب تک خدا تعالیٰ کی
طرف سے تو فیق نہیں ملتی.باوجود سامانوں کے اس کام کے کرنے کا جوش اور ہمت نہیں پیدا ہو
سکتی.دیکھو اگر کسی کو کچھ تکلیف پہنچے اور وہ پولیس میں رپورٹ کرے تو پولیس اس کی تحقیقات
کرے گی لیکن اگر پولیس کو حکام بالا کی طرف سے خاص طور پر اس کی تحقیقات کا حکم ہو تو وہ
بہت کوشش اور تندہی سے اس کام کو کرے گی.اس طرح خدا تعالیٰ نے ہر کام کے لئے
سامان پیدا کئے ہیں.لیکن جب خدا تعالیٰ ان کو یہ کہہ دے کہ میرے فلاں بندے کی مدد اور
تائید کرو تو سمجھ لو کہ وہ کس قدر زور سے کریں گے.تو صرف سامان کوئی چیز نہیں.اکثر اوقات
سامان کی موجودگی میں ناکامی ہوتی ہے.لیکن جب خدا تعالی کا حکم ہو جائے تو پھر کامیابی یقینی
ہوتی ہے.پس ہماری جماعت کو اس بات کی بڑی ضرورت ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی خاص خاص صفات
کو یاد کیا کرے اور اس سورہ کو پڑھا کرے تا کہ جن دلوں میں وساوس نہیں انہیں آئندہ بھی نہ
پڑیں اور جنہیں پڑے ہوں ان سے نکل جائیں.خدا تعالیٰ ہماری جماعت کو وساوس سے بچائے اور ان کے مقام کو بلند کرے کہ دنیا کی
نظروں سے اتنے ہی دور ہو جائیں جتنے ستارے ہیں.اور ان لوگوں میں ہمارا نام لکھا جائے جو
نبیوں اور صدیقوں اور شہیدوں کی جماعت ہے.( خطبہ جمعہ فرمودہ 22 ستمبر 1916ء - مطبوع افضل 3 اکتوبر 1916ء)
حضرت خلیفہ امسیح الثانی مخطبه جمعه فرمودہ 14اکتو بر 1918ء میں سورۃ الناس کی تشریح میں
فرماتے ہیں:
1172
Page 1181
انسان کے لیے جہاں ترقی اور کامیابی کی راہیں کھلی ہیں وہاں بہت سے سامان اس
کی ہلاکت کے بھی ہیں.اس میں کچھ بھی شک نہیں کہ انسان ترقی کرتے کرتے اعلیٰ سے اعلیٰ
مقام پر پہنچ جاتا ہے.اللہ تعالیٰ اس کا محب اور دوست ہو جاتا ہے.وہ خدا کے حضور ایسے مقام
پر کھڑا کیا جاتا ہے کہ اس پر وار کرنے والا اس پر وار کرنے کی بجائے خدا پر وار کرنے والا
قرار دیا جاتا ہے.خدا تعالیٰ اس کے اندر ہوتا ہے.باہر ہوتا ہے.آگے ہوتا ہے پیچھے ہوتا
ہے.اوپر ہوتا ہے.غرض ہر طرف سے وہ خدا کی پناہ میں ہوتا ہے.اس لیے جب وار کرنے
والا اس پر وار کرتا ہے تو اس کا وار اس پر پڑنے کی بجائے خدا کی کسی نہ کسی صفت پر پڑتا
ہے.پس وہ ایسے مقام پر ہوتا ہے کہ خدا کی صفات کا مظہر ہو جاتا ہے اور بعض لوگ دھو کہ میں
پڑ کر اسے خدا سمجھنے لگ جاتے ہیں.مگر باوجود اس کے اس میں بھی کچھ شک نہیں کہ جب انسان گرتا ہے تو انسانوں سے ہی
نہیں.بلکہ کسی وقت کتوں.سؤروں.گدھوں.ریچھوں اور بندروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے
اور کسی وقت نجاست کے کپڑوں سے بھی پلید تر ہو جاتا ہے.ترقی کرتا ہے تو اس مقام پر پہنچتا
ہے جس پر فرشتے بھی نہیں پہنچ سکتے اور اگر گرتا ہے تو ایسا گرتا ہے کہ ذلیل سے ذلیل مخلوق سے
بھی بدتر ہو جاتا ہے.ایک بزرگ کا واقعہ حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ایک صوفی تھے وہ پہاڑ پر رہتے
تھے.خدا تعالیٰ نے ان کے متعلق ایسا انتظام کیا تھا کہ ان کو دونوں وقت کھانا وہیں پہنچ جایا کرتا
تھا.کچھ عرصہ کے بعد ان کو یہ ابتلا پیش آیا کہ تین دن متواتر کھانا نہ ملا.جب بھوک سے
حالت خراب ہونے لگی تو وہ اپنی جگہ سے اٹھے اور قریب کے گاؤں میں گئے.اور ایک مکان
پر پہنچ کر کھانے کو مانگا.گھر والوں نے ان کو تین روٹیاں دیں.وہ روٹیاں لے کر واپس ہوئے
تو گھر والوں کے دروازے پر ایک کتا بیٹھا تھا وہ ان کے ساتھ ہولیا.انہوں نے اس کو آدھی
روٹی ڈال دی.مگر وہ کھا کر پھر ساتھ چلنے لگا.آدھی انہوں نے اور ڈال دی.وہ اس آدھی کو بھی
1173
Page 1182
کھا کر پیچھے چلا آتا رہا.انہوں نے ایک اور روٹی ڈال دی اور کہا کہ واقعی بیچارا ایک روٹی
سے کیا سیر ہوگا لیکن جب دو روٹیاں بھی کھا چکا تو پھر بھی ان کے پیچھے سے نہ ہٹا.انہوں نے
عصہ میں آکر تیسری روٹی بھی ڈال دی.اور کہا کہ تو بڑا بے حیا ہے جو پیچھا نہیں چھوڑتا.انسان
کی عادت ہے کہ جب وہ غصہ میں آتا ہے تو دیواروں اور درختوں کو بھی مخاطب کرلیا کرتا ہے.تو انہوں نے عنصہ کی حالت میں کتنے کو بے حیا کہا.اس پر کشفی طور پر اس کتے نے ان سے
گفتگو کی اور کہا کہ بے حیائیں ہوں کہ تو.خدا تجھ کو ہمیشہ رزق پہنچاتا تھا.مگر صرف تین دن نہ
پہنچا تو اٹھ کرلوگوں کے دروازوں پر مانگنے چلا آیا.مگر میں ہوں کہ ہمیشہ اپنے آقا کے دروازے
پر پڑا رہتا ہوں، خواہ ہفتوں فاقہ میں گزر جائیں.کتے کی اس گفتگو سے جو کشفی طور پر ہوئی تھی
ان کو اپنی کمزوری کا احساس ہو گیا.اس سے توبہ کی اور اپنے اس مقام پر جا بیٹھے اور خدا تعالیٰ
نے پھر ان کو اسی طرح کھانا پہنچانا شروع کر دیا.تو واقعی کتنے میں وفاداری کی صفت ایسی ہے
کہ وہ اپنے آقا کی خاطر جان بھی دے دیتا ہے اور ذرا پروانہیں کرتا.مگر انسان ایسے ہوتے ہیں
جو دوست وغیرہ کو مصیبت کے وقت چھوڑ دیتے ہیں.تو بعض انسان ایسے ہوتے ہیں جن میں کتے جتنی بھی وفا نہیں ہوتی.اسی طرح گدھے کو
احمق کہا جاتا ہے اور حماقت کے لیے گدھا مشہور ہے.لیکن بعض انسان اپنی حماقت میں
گدھے سے بھی بڑھ جاتے ہیں.گدھے میں اتنی تمیز ہوتی ہے کہ وہ کبھی شیر پر حملہ نہیں کرتا.بلکہ اس کی حس ایسی تیز ہوتی ہے کہ وہ شیر کی دُور سے ہی بُو سونگھ کر بھاگنے کی کوشش کرتا
ہے.لیکن انسان جب حماقت پر آتا ہے تو نہ صرف خدا کے پہلوانوں پر حملہ کرتا ہے.بلکہ خدا
کو بھی مقابلہ کا چیلنج دے دیتا ہے.گدھا احمق ہے مگر اتنا نہیں کہ خطرہ کی جگہ میں ٹھہرا ر ہے اور
شیر کی بو پاتے ہی اس کو چھوڑ نہ دے.لیکن انسان ایسا احمق ہوتا ہے کہ خدا کے سپہ سالاروں
کے مقابلہ میں چلا جاتا ہے.پھر انسان گرتے گرتے بندر سے بھی زیادہ نقال اور خنزیر سے بھی زیادہ بے حیا ہوجاتا ہے.اگر
1174
Page 1183
کسی جانور میں ایک ایک نقص ہے تو انسان میں تمام کے تمام نقائص جمع ہو جاتے ہیں.بے حیا
یہ ہوتا ہے.بے وفا یہ ہوتا ہے.اندھا تقلید کرنے والا یہ ہوتا ہے.احمق یہ ہوتا ہے.کبھی بھیڑ کی طرح مقلد ہو جاتا ہے.لوگوں کو نمازیں پڑھتا دیکھتا ہے تو خود بھی نماز
پڑھنے لگتا ہے لیکن کچھ نہیں سمجھتا کہ نماز کیوں پڑھتا ہوں؟ اور پھر لمبی نماز پڑھتا ہے کہ لوگ
تعریف کریں.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ میں ایسے لوگ پیدا ہوں
گے جو نما زمیں تو لمبی لمبی پڑھیں گے مگر ایمان ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا.یہ ایسے ہی
لوگوں کے متعلق آپ نے فرمایا..........اللہ تعالیٰ نے سورۃ الناس میں اس طرف توجہ دلائی ہے کہ کیونکر انسان انسانیت سے
گرتا ہے اور ساتھ ہی گرنے سے محفوظ رہنے کا طریق بتایا ہے.فرمایا قُلْ أَعُوذُ بِرَبّ
الناس یعنی تین ذریعے ہیں جن کے ذریعہ انسان او پر چڑھتا ہے اور تین ہی وہ ذریعے ہیں
جن سے نیچے گرتا ہے.ان تین ذرائع میں سے ایک ربوبیت ہے.دوسرا ملکیت ہے اور تیسرا
الوہیت.بہت دفعہ ربوبیت کے ذریعہ ابتلا آتا ہے اور بہت دفعہ ملکیت کے ذریعہ اور
بہت دفعہ الوہیت کے ذریعہ.اور پھر ان میں سے ہر ایک کی دو قسمیں ہیں.ایک نسبت فاعلی
کے لحاظ سے اور دوسری نسبت مفعولی کے لحاظ سے.یعنی کبھی انسان دوسروں کا رب بنتا ہے اور
کبھی دوسروں کو اپنا رب بنا تا ہے.پھر کبھی خود ملک بنتا ہے اور کبھی دوسروں کو اپنا ملک
بنا تا ہے.اسی طرح کبھی خود اللہ بنتا ہے اور کبھی دوسروں کو اپنا اللہ بنالیتا ہے.گویا تین سے
چھ ذریعے بن جاتے ہیں.کبھی یہ رب ہوتا ہے.یہ یاد رکھنا چاہیے کہ لفظ رب عام ہے.خدا کے لیے مثلاً
رب الناس آیا ہے.اس کے معنی ہیں پیدا کرنے والا.اور پھر ادنی حالت سے اعلیٰ کی طرف
لے جانے والا.اور بعض دفعہ رب کمر کہیں گے.اور اس کے معنی ہوں گے تمہارا سردار.تو
لغت والوں نے دونوں طرح لکھا ہے کہ لفظ رب بغیر اضافت یا باضافت خدا کے لیے آتا ہے
1175
Page 1184
اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ خدا کے سوا اوروں کے لیے بھی بول لیتے ہیں.بہر حال ایک ربوبیت
انسان کی ہوتی ہے.مثلاً اس کے غریب رشتہ دار ہیں اور وہ ان کی پرورش کرتا ہے.اس پر ابتلا
اس طرح آتا ہے کہ اس کے پاس اتنا رزق نہیں ہوتا کہ یہ ان کی پرورش کر سکے.اس لیے یہ
بعض ناواجب طریق اختیار کرتا ہے.چوری کرتا ہے.رشوت لیتا ہے.اسی طرح کسی کو اپنا
رب سمجھتا ہے.اس کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے.یا اور اسی قسم کی باتیں کرتا ہے تو
خدا کی ربوبیت کو بھول جاتا ہے اور بندوں کو اپنا رب بنا لیتا ہے.دوسرا ذریعہ ملکیت ہے.یعنی بعض بادشاہ ہوتے ہیں تو ان کے بادشاہ ہونے کی حیثیت
میں ان پر رعیت کے کچھ حقوق عائد ہوتے ہیں.وہ ان میں خیانت کرتے ہیں.یا خودرعیت
ہوتے ہیں اور دوسرا ملک ہوتا ہے تو رعیت ہونے کی حالت میں بغاوت یا دیگر قسم کے سیاسی
جرم کرتے ہیں.تیسری شق الوہیت ہے کہ کبھی تو انسان خود اللہ بن جاتا ہے.اور کبھی دوسروں کو الہ بنالیتا
ہے.حضرت خلیفہ اول جب اپنے ایک استاد سے رخصت ہونے لگے تو انہوں نے آپ کو کہا
کہ میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں اور وہ یہ کہ تم کبھی خدا بننے کی خواہش نہ کرنا.حضرت مولوی
صاحب نے حیران ہو کر پوچھا کہ کیا خدا بھی کوئی بنتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ زبان سے خدا
ہونے کا تو بہت کم لوگ دعویٰ کرتے ہیں مگر عملاً بہت لوگ خدائی کا دعوی کرتے ہیں اور وہ اس
طرح کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو کچھ ہم کہیں وہی ہو کر رہے.حالانکہ یہ بات تو خدا کے شایانِ شان
ہے.جولوگ قولا دعویٰ کرتے ہیں ان کا علاج تو عام لوگ بھی کر لیا کرتے ہیں.جیسا کہ مشہور
ہے کہ ایک شخص نے خدائی کا دعویٰ کیا.علماء نے اسے بہتیر اسمجھایا.مگر وہ باز نہ آیا.ایک
ان پڑھ تھا.وہ بہت کوشش کرتا تھا کہ مجھے موقع ملے تو میں اس کو سمجھاؤں.مگر خدائی کے
مدعی کے چیلے ہر وقت اس کے ارد گرد جمے رہتے تھے.اتفاقاً ایک دن جبکہ وہ اکیلا تھا تو اسے
موقع ملا.وہ اس کے پاس گیا اور جا کر دریافت کیا کہ کیوں جی آپ خدا ہیں ؟ اس نے کہا ہاں.1176
Page 1185
اُس ان پڑھ نے اسے گردن سے پکڑ لیا اور کہا کہ اچھا ہوا آج تو مجھے مل گیا ہے.میں تو مدتوں
سے تیری تلاش میں تھا.آج تیری خبر لوں گا.یہ کہہ کر اسے مارتا جاتا تھا اور کہتا جاتا تھا کہ تُو
نے ہی میرے فلاں رشتہ دار کو مارا ہے.اب تو میرے قابو آیا ہے.میں تجھ کو ہر گز نہیں
چھوڑوں گا.جب بہت مار پڑی تو اس نے کہا مجھے چھوڑ دے میں خدا نہیں ہوں.پس ٹھوکر لگنے کے تین ذریعے ہیں.ربوبیت.ملکیت.الوہیت.اس لئے اللہ تعالیٰ اس کا
علاج بتاتا ہے.قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاس کہ اس بات کا یقین
رکھو کہ ربّ النّاس کے سوا کوئی رب نہیں.مَلِكِ النَّاس اصل بادشاہ تو وہ ہے جو خدا ہے.إله الناس اور معبود بھی وہی ہے.اس لیے کہو کہ میں اس خدا کی پناہ میں آتا ہوں جو رب
ہے.ملک ہے اور اللہ ہے اس دعا میں ایک لطیف نکتہ ہے.اسلام کی تمام دعاؤں میں ایسے الفاظ اور ایسا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے جس سے خدا کی غیرت
کو جوش آئے.کہا جا سکتا ہے کہ بجائے خدا کی تین صفات کے ذکر کرنے کے کیوں نہ صرف
اله الناس کہہ دیا کہ لفظ الہ میں تینوں مراتب اور صفات بھی آجاتے.مگر ا گر صرف لفظ اللہ کو
رکھا جاتا تو وہ بات پیدا نہ ہوتی جو اس تفصیل سے پیدا ہوتی ہے.خدا رب ہے تو رب الناس
کہ کر گویا خدا کی غیرت کو جوش دلایا ہے کہ لوگوں کا رب تو یہ ہے.پھر اور کوئی کس طرح رب
ہوسکتا ہے.اسی طرح باقی دونوں صفات میں بھی خدا کی غیرت کو جوش میں لایا گیا ہے.اور یہ
ایسی بات ہے کہ ہر شخص اس کو مشاہدہ کر سکتا ہے اور خدا تعالیٰ نے خود شرک کے متعلق کس قدر
غیرت کا اظہار فرمایا ہے.اس لیے جہاں ٹھوکر لگنے کا خطرہ تھا اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے
ایسی دعا تلقین کی کہ جس سے خدا کی غیرت کو جوش آئے اور وہ اپنے بندوں کو تمام خطرات سے
محفوظ رکھے.تو انسان کو ٹھوکروں سے بچنے کے لیے کس چیز سے پناہ مانگنا چاہیے.فرمایا :
مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الخنّاس - خناس کے وسوسوں سے.وسوسہ ڈالنے والے ہمیشہ ایسے طریق اختیار کرتے ہیں جو بہت پوشیدہ ہوتے ہیں اور
1177
Page 1186
نہایت چالاکی سے کوئی بد عقیدگی اور بدعملی سکھا دیتے ہیں.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص اس
دعا کو پڑھے گا اور خدا کی ربوبیت، ملکیت، الوہیت کو ذہن میں رکھے گا وہ ضرور ایسے وساوس
سے بچ جائے گا.وسوسہ انداز چپکے سے ایک شوشہ چھوڑ دیتے ہیں اور کمزور آدمی کو ایسی جگہ سے
پکڑتے ہیں کہ جہاں ان کا وار اثر کر سکے.لدھیانہ میں ایک شخص میر عباس علی تھے.وہ حضرت صاحب سے بہت خلوص رکھتے تھے
حتی کہ ان کی موجودہ حالت کے متعلق حضرت صاحب کو الہام بھی ہوا تھا.لدھیانہ میں جب
حضرت مسیح موعود اور محمد حسین کا مباحثہ ہوا تو میر عباس علی حضرت صاحب کا کوئی پیغام لے کر
گئے.ان کے مولوی محمد حسین وغیرہ مولویوں نے بڑے احترام اور عزت سے ہاتھ چومے اور کہا
آپ آل رسول ہیں.آپ کی تو ہم بھی بیعت کر لیں لیکن یہ مغل کہاں سے آ گیا.اگر کوئی مامور
آتا تو سادات میں سے آنا چاہیے تھا.پھر کچھ تصوف و صوفیاء کا ذکر شروع کر دیا.میر صاحب کو
صوفیاء سے بہت اعتقاد تھا.مولویوں نے کچھ ادھر اُدھر کے قصے بیان کر کے کہا کہ صوفیاء تو
اس قسم کے عجوبے دکھایا کرتے تھے.اگر مرزا صاحب میں بھی کچھ ہے تو کوئی عجوبہ دکھلائیں.ہم آج ہی ان کو مان لیں گے.مثلاوہ کوئی سانپ پکڑ کر دکھائیں.یا اور کوئی اسی قسم کی بات
کریں.میر عباس علی کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی.اور جب حضرت صاحب کے پاس آئے تو
کہا کہ حضور اگر کوئی کرامت دکھائیں تو سب مولوی مان لیں گے.حضرت صاحب فرماتے
ہیں کہ جب کرامت کا لفظ ان کی زبان سے نکلا تو اسی وقت مجھے یقین ہو گیا کہ بس میر صاحب کو
مولویوں نے پھندے میں پھنسا لیا.اس پر حضرت صاحب نے ان کو بہت سمجھایا مگر ان کی سمجھ
میں کچھ نہ آیا.تو وسوسہ انداز لوگ ایک سوراخ تلاش کرتے ہیں اور اس کے ذریعہ انسان کے
دل میں وسوسہ ڈال دیتے ہیں جس سے اسے ٹھوکر لگ جاتی ہے.قادیان میں بھی ایسے لوگ ہیں جن کا یہ کام ہے کہ لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالیں.بیعت
بھی کی ہوئی ہے.اپنے آپ کو مخلص بھی قرار دیتے ہیں.مگر وسوسہ اندازی سے باز نہیں آتے.1178
Page 1187
ایسے لوگوں سے محفوظ رہنے کا ایک ہی ذریعہ ہے.اور وہ یہ کہ انسان سچے دل سے أَعُوذُ بِرَبّ
الناس پڑھے.جو پڑھے گا یقینا اللہ تعالیٰ اسے وسوسہ سے محفوظ رکھے گا.کیونکہ اللہ تعالی کسی
کے اخلاص کو ضائع نہیں کرتا اور شیطان غالب نہیں آسکتا.شیطان کو اقتدار نہیں دیا گیا.پس
جب تم سچے دل سے اس سورۃ کو پڑھو گے اور اس کے مفہوم ومطلب کو ذہن میں رکھو گے تو
شیطان بھاگ جائے گا.لیکن جو لوگ اس کی طرف توجہ نہیں کریں گے وہ وساوس میں پڑ
جائیں گے اور ان پر شیطان کا قبضہ ممکن ہے.پس ہم سب رَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلهِ
النّاس کی پناہ میں آتے ہیں.اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کے وساوس سے بچائے.“
( خطبه جمعه فرموده 4 اکتوبر 1918 ء ، خطبات محمود ( سال 1918 ) صفحه 108 تا114 )
حضرت خلیفتہ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے ماہ رمضان المبارک 2016 ء
کے آخری روز مسجد فضل لندن میں قرآن مجید کی آخری تین سورتوں کا درس ارشاد فرمایا.حضور انور
ایدہ اللہ نے اس میں سورۃ الناس کا درس دیتے ہوئے فرمایا:
پھر آخری سورۃ جو ہے سورۃ الناس ہے.اس کا ترجمہ یہ ہے بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ
الرَّحِیمِ.اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا ہے، بن مانگے دینے والا ہے اور
بار بار رحم کرنے والا ہے.قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ تُو کہہ دے کہ میں انسانوں کے رب کی پناہ
مانگتا ہوں.مَلِكِ الناس انسانوں کے بادشاہ کی.اله الناس انسانوں کے معبود کی.من
شَرِّ الْوَسْوَاسِس الخناس بکثرت وسوسے پیدا کرنے والے کے شر سے جو وسوسہ ڈال کر پیچھے
ہٹ جاتا ہے.الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ وہ جو انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا
ہے.مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ خواہ وہ جنوں میں سے ہو یعنی بڑے لوگوں میں سے یا عوام الناس
میں سے.اس سورۃ میں ان شرور سے بچنے کا روحانی علاج بتایا گیا ہے کہ اپنے معبود حقیقی کو پہچانو گے تو
ان شرور سے بچتے رہو گے جو اندرونی اور بیرونی دونوں طرح کے شر ہیں.1179
Page 1188
سورۃ الفلق اور سورۃ الناس خاص طور پر مسیح موعود کے زمانے سے تعلق رکھنے والی ہیں اس
لئے ہر احمدی کو انہیں پڑھنا چاہئے اور سمجھنا بھی چاہئے اور ان میں جن شرور کا ذکر ہوا ہے خاص
طور پر ان سے بچنے کے لئے دعا بھی کرنی چاہئے اور کوشش بھی کرنی چاہئے.سورۃ الناس میں اللہ تعالیٰ کی تین اہم صفات کا ذکر کیا گیا ہے.اللہ تعالی کی پناہ مانگی گئی
ہے یعنی رب الناس كی.مَلِكِ النّاس کہ بادشاہ ہے لوگوں کا.الہ الناس.جو معبود ہے
لوگوں کا.اور بتایا گیا ہے کہ جب بڑے منصوبہ بندیاں کرنے والے اور ہوشیار حاسد پیدا ہوں
گے تو ان کا مقابلہ روحانی طاقت سے ہی ہو سکے گا اور کوئی ذریعہ نہیں.اور اس کے حاصل
کرنے کے لئے رب الناس کی پناہ میں آؤ جو تمہارا بھی رب ہے اور ہر ایک کا رب ہے.یہ
نہ سمجھو کہ کوئی دنیاوی وسیلہ تمہاری پرورش کا سامان کرتا ہے یا تمہاری دنیاوی ترقیات دنیا والوں
کو اپنا رب ماننے سے ہوں گی.یعنی جو حقیقی رب ہے اس کو رب بناؤ جس سے روحانیت بھی
ترقی کرے اور اللہ تعالیٰ پھر دنیاوی انعامات بھی دیتا ہے.اس ملک کی پناہ میں آؤ جو تمہارا
بھی بادشاہ ہے اور ہر ایک کا بادشاہ ہے.اس کی بادشاہی ہر ایک پر حاوی ہے.اس لئے بڑی
طاقتوں کی بادشاہی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں.اس معبود کی پناہ میں آؤ جو تمہارا معبود ہے
اور حقیقی معبود ہے اور اس حقیقی معبود کے علاوہ کوئی غیر الہ، غیر معبود تمہیں متاثر نہ کرے.یادرکھو
تمہارے رزق، تمہاری پرورشیں ، پرورشوں کے سامان مہیا کرنے والا ، تمہاری پرورش کرنے والا
صرف ایک خدا ہے، کوئی دنیا وی طاقت نہیں.حقیقی بادشاہ خدا تعالیٰ ہے، اور کوئی نہیں.پس ایک حقیقی مومن کو اور من حیث الجماعت مسلم اللہ کو یہ دعا سکھائی گئی ہے کہ جب
دنیاوی طاقتیں اپنے زعم میں اپنے آپ کو رب سمجھنے لگ جائیں، جب دنیاوی طاقتیں اپنی بڑی
حکومتوں کے زعم میں اپنے آپ کو ملک سمجھنے لگ جائیں ، جب وہ کھلے الفاظ میں نہ سہی لیکن
اپنے عمل سے یہ اظہار کر رہی ہوں کہ ہمارے آگے جھکو تو اس وقت تمہیں سب کچھ ملے گا تو اس
وقت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک حقیقی مومن کا فرض ہے کہ اللہ تعالی کی پناہ حاصل کرو، اس کی
1180
Page 1189
پناہ میں آنے کی کوشش کرو.مسلمان دنیا میں جو آجکل ہو رہا ہے یہ اسلام کے خلاف ایک سازش ہے.صرف مسلمان
آپس میں نہیں لڑ رہے بلکہ اسلام مخالف طاقتیں ہیں جو بڑے طریقے اور دجل سے ان ملکوں
میں فساد پیدا کر رہی ہیں اور پھر ہمدرد بن کر ان پر ہاتھ رکھ کر یہ باور کرانے کی کوشش کی جارہی
ہے کہ دیکھو ہمیں تمہاری بھلائی ، تمہاری بہتری اور تمہاری پرورش کا کتنا خیال ہے.تمہاری
حکومتوں نے تو تمہارے حق ادا نہیں کئے لیکن ہم تمہارے حق ادا کریں گے اور کر رہے ہیں اور
بعض مسلمانوں پر ان فساد زدہ علاقوں میں اس کا اثر بھی ہورہا ہے.گزشتہ دنوں ایک خبر تھی کہ ان
فساد زدہ علاقوں کے کئی مسلمان عیسائی ہو گئے.کچھ کا تو خیال ہے کہ یہ لوگ اپنی بھوک اور اپنا
ننگ مٹانے کے لئے عیسائی ہوتے ہیں.کچھ کا خیال ہے کہ حقیقت میں مسلمانوں کے عمل
دیکھ کے اور ان کے دجل میں آکے یہ عیسائی ہوتے ہیں.بہر حال یہ ایک چال چلی جا رہی
ہے جس نے مسلمان دنیا میں ایک فساد پیدا کیا ہوا ہے.دونوں فریقوں کو اسلحہ دینے والے بھی
یہی لوگ ہیں اور دونوں کی صلح کرانے کے لئے آگے آنے والے بھی یہی لوگ ہیں اور پھر اس
بہانے سے غیر محسوس طریقے سے ان مسلمان ملکوں کی دولت سے فائدہ اٹھانے والے بھی یہی
لوگ ہیں.اب ان کے اپنے لکھنے والے وہ لوگ جو انصاف دیکھنا چاہتے ہیں یا انصاف پسند ہیں بعض
تبصرے کرنے لگ گئے ہیں کہ ہمارے لوگ ہی ہیں جن کی غلطیوں کی وجہ سے فساد پیدا ہوا ہے.بہر حال ایک شیطانی فتنہ ہے جو تین ذریعوں سے جاری ہے.پھر شیطانی فتنہ اس کے
علاوہ بھی ہے.یہ تو انفرادی طور پر ایک بڑے فساد ہیں.اخلاقی طور پر مذہب سے دور لے
جانے کے لئے خاندانوں میں، قوموں میں اسلام پر عمل کرنے والوں کے اندر بے چینی اور
فرسٹریشن (frustration) پیدا کرنے کے لئے کہیں عورتوں کے حقوق کی تنظیمیں بنائی جاتی
ہیں.اس میں چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر ان پر بڑا شور مچایا جاتا ہے.کئی جگہ یہی ایشو بن گیا
1181
Page 1190
کہ اگر عورت سے مصافحہ نہیں کرتے تو عورت کے حق نہیں ادا کئے.سویڈن میں مجھ سے کسی
اخباری نمائندے نے کہا.میں نے کہا دنیا میں بہت سارے اور بڑے مسائل ہیں.اگر
تمہارے خیال میں تمہاری قوم کی ترقی ، ملک کی ترقی اور دنیا کے فسادصرف عورت سے مصافحہ کر
کے ہی حل ہو سکتے ہیں تو پھر ثابت کر کے دکھاؤ یہاں تم کتنا فائدہ اٹھا رہے ہو.یا صرف عورت
کی عزت مصافحہ کرنے میں ہی ہے؟ اسلام کی جو تعلیم ہے ہم مسلمان اس پر عمل کرنے کی
کوشش کرتے ہیں.تم لوگ مذہب سے ہٹے ہوئے ہو اس لئے اس سے دُور جا ر ہے ہو.پھر شیطانی فتنہ آجکل جو زوروں پر ہے ہم جنسی کی باتیں کرتے ہیں.یہ بھی خناس ہے،
شیطان ہے جو مختلف طریقوں سے وسوسے پیدا کرتا ہے.سویڈن میں ایک جگہ
ریسپشن (reception) تھی تو جب میں نے اس کے خلاف بات کی تو وہاں کی پارلیمنٹ
کے ممبروں نے فیصلہ کیا کہ ہم فنکشن میں شامل نہیں ہوں گے.میں نے کہا بیشک نہ شامل
ہوں.جو اسلام کی تعلیم ہے اور نہ صرف اسلام کی تعلیم بلکہ ہر مذہب
کی تعلیم ، بائبل اس پر سب
سے زیادہ بولتی ہے، اس کے خلاف جو کام ہو گا وہ ہم نہیں کریں گے.لیکن بہر حال اس کے
باوجود چند ایک لوگ تو نہیں آئے یا اس پارٹی کے لوگ نہیں آئے جن کا خیال تھا کہ ہماری
حکومتیں صرف اسی شیطانی کام کی وجہ سے بچی ہوئی ہیں ، ان کے علاوہ اکثر لوگ آئے اور بڑا
کامیاب ہوا.تو بہر حال ہم نے، جماعت احمدیہ کے ہر ممبر نے ، ہر احمدی نے یہ کوشش کرنی
ہے کہ شیطان کے جو فتنے ہیں، قانون بنا کے یا مختلف اور طریقوں سے وسوسے ڈالنے والے
ہیں، ہر ذریعہ سے اس کے خلاف قدم اٹھانا ہے اور اس روحانی روشنی کو دنیا میں پھیلانا ہے جو
حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعہ سے آئی ہے.پس اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ میں یہ دعا سکھلائی ہے کہ تم اس شیطان سے بچنے کی دعا کرو اور
بجائے دنیاوی طریقوں کو اختیار کرنے کے روحانیت میں بڑھنے کی کوشش کرو.بجائے ان
بادشاہوں کے غیر اسلامی قوانین کی حمایت کرنے کے، اور ان سے ڈرنے کے بجائے کھل کر
1182
Page 1191
اپنے دین پر قائم ہو.اللہ تعالیٰ نے جو روشنی اس زمانے میں اتارنی تھی وہ اتار دی اور ہم
خوش قسمت ہیں کہ ہمیں اس کو ماننے کی توفیق بھی دی.اب اس کو پھیلانا بھی ہمارا کام ہے اور
لوگوں کو بتانا کہ یہ روشنی ہے اس کو تلاش کرو.اللہ تعالیٰ کرے کہ مسلمانوں کو بھی ان باتوں کی
سمجھ آ جائے اور احمدیوں کو بھی اس کے لئے بہت زیادہ کوشش اور دعا کرنی چاہئے.(ماخوذ از ہفت روزہ الفضل انٹرنیشنل 24 فروری 2017، صفحہ 4)
حضرت خلیفة المسیح الخامس اليد واللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے ماہ رمضان المبارک 2017ء
کے آخری روز قرآن مجید کی آخری تین سورتوں کا درس دیتے ہوئے فرمایا کہ:
سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خود بھی لکھا ہے
کہ یہ خاص طور پر مسیح موعود کے زمانے سے تعلق رکھنے والے مسائل اور حالات سے متعلق ہیں اور
ان کا حل ہیں.اس لئے ہر احمدی کو اس کی گہرائی کو سمجھنا چاہئے اور باقاعدگی سے پڑھنا چاہیئے.سورۃ الناس میں اللہ تعالیٰ کی تین اہم صفات کا ذکر کیا گیا ہے.اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی گئی
ہے یعنی رب الناس ، ملک الناس اور الہ الناس کہہ کر.اس میں اس بات پر روشنی ڈالی کہ جب
بڑے ہشیار اور طاقتور حاسد پیدا ہوں گے تو ان کا مقابلہ روحانی طاقت کے علاوہ اور کسی ذریعہ
سے نہیں ہوسکتا.اللہ تعالیٰ کی مدد کے علاوہ اور کسی ذریعہ سے نہیں ہو سکتا.حضرت مسیح موعود
علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں.بڑا وسوسہ یہ ہے کہ ربوبیت کے متعلق غلطیاں ڈالی جائیں
جیسا کہ امیر لوگوں کے پاس بہت مال و دولت دیکھ کر انسان کہے کہ یہی پرورش کرنے والے
ہیں.اس واسطے حقیقی رب الناس کی پناہ چاہنے کے واسطے فرمایا.پھر دنیاوی بادشاہوں اور
حاکموں کو انسان مختار کل سمجھنے لگ جاتا ہے.سمجھتا ہے کہ ان کے پاس سارے اختیارات
ہیں.آپ فرماتے ہیں کہ اس پر فرمایا مَلِكِ النّاس.اللہ ہی ہے اللہ کے علاوہ اور کوئی
بادشاہ نہیں.پھر فرماتے ہیں کہ لوگوں کے وساوس کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ مخلوق کو خدا کے برابر
ماننے لگ جاتے ہیں اور ان سے خوف و رجا رکھتے ہیں.خدا سے زیادہ مخلوق کا خوف کرنے
1183
Page 1192
لگ جاتے ہیں اس واسطے الهِ النّاس فرمایا.فرمایا کہ یہ وسوسے ڈالنے والا شیطان ہے اور
یہ چھپ کر حملہ کرتا ہے اس لئے ان مخفی حملوں سے بچنے کے لئے دعا کرو اور ہمیشہ اس بات پر قائم
رہو اور اس کی پناہ میں آنے کی کوشش کرو جو تمہارا بھی رب ہے اور ان ظاہری دنیا وی ربوں
کا بھی رب ہے.اس مالک کی پناہ میں آؤ جو تمہارا بھی مالک ہے اور ہر ایک کا مالک
ہے.اس کی بادشاہی ہر ایک پر حاوی ہے اس لئے بڑی طاقتوں کی بادشاہی سے ڈرنے کی
ضرورت نہیں ہے.اسی طرح اس معبود کی پناہ میں آؤ جو تمہارا معبود حقیقی ہے اور اس کی
عبادت کا حق ادا کرو کیونکہ اس معبود حقیقی کے علاوہ غیر معبود یا الہ تم پر کوئی اثر نہیں ڈال سکتا.اگر اس سے سچا تعلق ہے تو پھر سب اللہ جو ہیں وہ ہوا میں اڑ جائیں گے.ہمیشہ یاد رکھو تمہیں
رزق دینے والا تمہاری پرورش کرنے والا صرف ایک خدا ہے.پس اس سے جڑ جاؤ.پس
مومنین کو اور امت مسلمہ کو یہ دعا سکھائی کہ جب دنیاوی طاقتیں اپنے آپ کو رب اور مالک
سمجھنے لگ جائیں اور یہ تاثر دیں کہ اب اگر فائدے اٹھانے ہیں، اب اگر اپنی زندگیوں کو
آسان بنانا ہے، اگر اب ترقیات حاصل کرنی ہیں تو ہمارے آگے جھکو ہماری عبادت کرو تو اس
وقت اس بات کو یا درکھنا کہ اصل رب، اصل مالک، اصل معبود خدائے واحد ہی ہے.اگر
اس سے تعلق جوڑ لو گے تو کوئی دنیاوی طاقت کوئی شیطانی طاقت کوئی حیلہ تمہیں متاثر نہیں کر
سکتا تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا.(ماخوذ از الفضل انٹرنیشنل 14 جولائی 2017 صفحہ 16-17 )
حضرت خلیفہ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے خطبہ جمعہ فرمودہ 16 فروری
2018ء میں قرآن کریم کی آخری تین سورتوں کی اہمیت اور ان کے پر معارف مضامین کی
طرف توجہ دلاتے ہوئے فرمایا:
قرآن کریم میں ہی اللہ تعالیٰ نے بہت سی دعائیں مختلف انبیاء کے حوالے سے بتائی ہیں
جو ہم نماز میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور چلتے پھرتے ذکر کے طور پر بھی پڑھتے ہیں اور پڑھ سکتے
1184
Page 1193
ہیں.لوگ اپنے خطوں میں لکھتے ہیں کہ ہمیں فلاں مشکل ہے، فلاں پریشانی ہے، کوئی دعا اور
ذکر بتائیں جس کا ورد ہم کرتے رہا کریں اور ہماری مشکلات اور پریشانیاں دُور ہوں.عموماً
لوگوں کو میں یہی لکھتا ہوں کہ نمازوں کی طرف توجہ دیں.سجدوں میں دعائیں کریں.نماز میں
دعائیں کریں.اور اپنے خدا تعالیٰ سے مدد مانگیں.لیکن آج میں ایک ذکر کے بارے میں بھی
بتانا چاہتا ہوں جو آ نحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور خدا تعالیٰ کی طرف سے اتری
ہوئی دعائیں بھی ہیں اور جس کے مطالب پر غور کر کے پڑھنے سے جہاں انسان
اللہ تعالیٰ کی
توحید کا ادراک حاصل کرتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور پناہ میں بھی آتا ہے اور ہر قسم کے
شرور سے بھی محفوظ رہتا ہے.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ خود با قاعدگی سے روزانہ
رات کو سونے سے پہلے ان آیات اور دعاؤں کو پڑھا کرتے تھے بلکہ صحابہ کو بھی پڑھنے کی
تلقین فرماتے تھے اور بہت ساری جگہوں پر ان دعاؤں کی ان آیات کی اہمیت بیان فرمائی.آپ نے اس کے فوائد بیان فرمائے.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ذاتی عمل کے
بارے میں اس سلسلہ میں روایت آتی ہے.روایت میں آتا ہے کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سوتے وقت آیتہ الکرسی، سورۃ اخلاص،
سورۃ فلق اور سورۃ الناس یعنی قرآن کریم کی جو آخری تین سورتیں ہیں، یہ اور آیۃ الکرسی تین دفعہ
پڑھ کر ہاتھوں پر پھونکتے اور پھر اپنے ہاتھوں کو جسم پر اس طرح پھیر تے کہ سر سے شروع کر کے
جہاں تک جسم پر ہاتھ جا سکتا جسم پر پھیرتے.پس جس کام کو آپ نے باقاعدہ جاری رکھا یا با قاعدگی سے کیا تو یہ آپ کی سنت بنی اور اس
کام کو ہر مسلمان کو کرنا چاہیئے اور ہم احمدی جن کی اس زمانے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
ہر سنت پر عمل کرنے کی طرف حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید رہنمائی فرمائی
ہے ہمیں اس پر عمل کرنے کی خاص کوشش کرنی چاہئے اور خاص طور پر ان حالات میں جن
میں سے ہم گزر رہے ہیں دعاؤں اور نمازوں اور اذکار کی طرف خاص طور پر نہ صرف اپنی ذاتی
روحانی اور دنیاوی ضروریات کے لئے توجہ دینی چاہئے بلکہ جماعتی فتنوں اور فسادوں اور حاسدوں
1185
Page 1194
اور دشمنوں کے شر سے بچنے کے لئے بھی ایک انتہائی اہم فرض سمجھ کر توجہ دینی چاہئے.اس ذکر اور آیات کی اہمیت بعض اور احادیث سے بھی ملتی ہے جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں.جہاں تک آیتہ الکرسی کا تعلق ہے اس کے بارے میں دو جمعہ پہلے میں بیان کر چکا ہوں.آج قرآن کریم کی آخری تین سورتوں کے بارے میں احادیث کے حوالے سے بات
کروں گا.کس طرح بار بار اور مختلف رنگ میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ
کو ان سورتوں کے پڑھنے کے بارے میں تلقین فرمائی ہے.ایک روایت میں آخری تینوں قل پڑھ کرجسم پر پھونکنے کے بارے میں حضرت عائشہ اس طرح
بیان فرماتی ہیں.فرمایا کہ ہر رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر لیٹتے تو اپنی ہتھیلیوں کو
جوڑتے اور پھر ان پر پھونکتے اور ان میں یہ پڑھتے قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ.وَقُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ.وقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ.یعنی یہ تینوں سورتیں پڑھتے اور پھر جہاں تک ممکن ہوتا دونوں ہاتھوں
کو جسم پر پھیرتے.آپ اپنے سر اور چہرے سے دونوں ہاتھ پھیر نا شروع کرتے اور پھر جو جسم کا
حصہ آ تاجہاں تک آپ
کا ہاتھ جا سکتا تھا آپ تین بار ایسا کرتے.( صحیح بخاری.کتاب فضائل القرآن.باب فضل المعوذات)
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام اس با قاعدگی سے فرماتے تھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ
تعالیٰ عنہا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بیماری میں خود یہ دعائیں پڑھتیں اور آپ کے
ہاتھوں پر پھونک کر آپ کے ہاتھ ہی آپ کے جسم پر پھیر تیں.چنانچہ حضرت عائشہ سے
روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوتے تو معوذات پڑھ کر اپنے اوپر
پھونکتے.کہتی ہیں جب آپ کی بیماری سخت ہوگئی تو میں یہ سورتیں آپ پر پڑھتی اور آپ کے
ہاتھ ان کی برکت کی امید سے آپ پر پھیرتی.( صحیح بخاری.کتاب فضائل القرآن.باب فضل المعوذات)
پس یہ خیال حضرت عائشہ کو آنا یقیناً اس وجہ سے تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس میں
بہت با قاعدہ تھے اور اس کی برکت کی اہمیت حضرت عائشہ پر خوب کھول کر واضح فرمائی تھی.1186
Page 1195
پھر صحابہ کو ان سورتوں کی برکات اور اہمیت کا کس طرح احساس دلایا.اس بارے میں
حضرت عقبہ بن عامر بیان کرتے ہیں کہ میری رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی.آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر میرا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا اے عقبہ بن عامر.کیا میں تمہیں
تورات اور انجیل اور زبور اور فرقان عظیم میں جوسورتیں اتاری گئی ہیں ان میں سے تین بہترین
سورتوں کے بارے میں نہ بتاؤں.میں نے عرض کی.کیوں نہیں.اللہ مجھے آپ پر فدا کرے.پھر آپ نے مجھے قُلْ هُوَ اللهُ اَحَدٌ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ اور قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ
الناس پڑھ کر سنائیں.پھر فرمایا اے عقبہ ! تم انہیں مت بھولنا اور کوئی رات ایسی نہ گزارنا
جب تک تو انہیں پڑھ نہ لے.عقبی کہتے ہیں کہ جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ
تو انہیں نہ بھولنا.تو اس وقت سے میں انہیں نہیں بھولا اور میں نے کوئی رات ایسی نہیں گزاری
جب تک میں نے انہیں پڑھ نہ لیا ہو.( مسند احمد بن حنبل "مسند عقبہ بن عامر جلد 5 صفحہ 895-896 مطبوعہ بیروت.ایڈیشن
1998 ء.حدیث نمبر 17467)
پس آپ کا یہ فرمانا کہ تم انہیں مت بھولنا اور کوئی رات ایسی نہ گزارنا کہ جب تک انہیں
پڑھ نہ لو، صاف ظاہر کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کس با قاعدگی کے ساتھ اس کو پڑھا
کرتے تھے.اللہ تعالیٰ کی باتوں پر، احکامات پر ، دعاؤں پر سب سے زیادہ عمل کرنے والے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور تبھی آپ دوسروں کو فرمایا کرتے تھے.پھر سورۃ اخلاص کی اہمیت کے بارے میں یعنی قُل هُوَ اللهُ أَحَدٌ جو سورت شروع ہوتی
ہے اس کے بارے میں ایک حدیث میں اس طرح ذکر ملتا ہے.حضرت ابوسعید خدری
روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک آدمی کو قُل هُوَ اللهُ أَحَدٌ پڑھتے ہوئے سنا جو اس
کو بار بار پڑھ رہا تھا.جب صبح ہوئی تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر
ہو کر ساری بات بیان کی اور گویا کہ وہ اس شخص کو کم یا چھوٹا سمجھ رہا تھا اس لئے شکایت کے
رنگ میں بیان کیا.اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا.قسم ہے اس ذات کی جس
1187
Page 1196
کے ہاتھ میں میری جان ہے یہ قرآن کے تیسرے حصہ کے برابر ہے.( صحیح بخاری.کتاب فضائل القرآن - باب قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ )
حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ضمن میں ایک جگہ تفصیل یوں بیان کرتے ہیں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا: کیا تم میں سے کوئی اس بات سے
عاجز ہے کہ ایک رات میں ایک تہائی قرآن مجید پڑھے.یہ بات صحابہ پر بڑی گراں گزری.انہوں نے کہا یا رسول اللہ ! ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے کہ ایک تہائی قرآن کریم
رات میں پڑھ لے.آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ الواحد الصمد.یعنی سورۃ
اخلاص ایک تہائی قرآن ہے.( صحیح بخاری.کتاب فضائل القرآن - باب قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ )
سورۃ اخلاص کے قرآن کریم کے تیسرے حصہ کے حوالے سے صحیح مسلم نے ایک روایت
اس طرح لکھی ہے.حضرت ابو ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول
اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا تم جمع ہو جاؤ میں تمہیں قرآن کا تیسرا حصہ پڑھ کر سناؤں گا.ساروں کو اکٹھا
کیا، جمع کیا کہ مسجد میں آ جاؤ.پس لوگ اکٹھے ہو گئے.پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر
تشریف لائے اور قُلْ هُوَ اللهُ اَحَد کی تلاوت فرمائی.پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف
لے گئے.صحابہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے کسی نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ آسمان سے کوئی خبر یعنی
وحی آئی ہے جس کی وجہ سے آپ اپنے گھر میں داخل ہوئے ہیں اور اندر چلے گئے ہیں.پھر نبی
کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور فرمایا میں نے تم سے کہا تھا کہ میں تم پر قرآن کا
تیسرا حصہ پڑھوں گا.غور سے سنو یہ سورۃ اخلاص قرآن کے تیسرے حصہ کے برابر ہے.( صحیح مسلم - کتاب صلوة المسافرين و قصرها - باب فضل قراءة قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ )
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تیسرا حصہ کیوں کہا؟ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم
کو تو حید کو ثابت کرنے اور اس کے قیام کے لئے نازل فرمایا.پس اس سورۃ میں بڑے واضح
الفاظ میں اور جامع انداز میں توحید کو بیان کیا گیا ہے.پس اس کے الفاظ پر غور کرنے اور عمل
کرنے سے انسان حقیقی توحید پر عمل کر سکتا ہے اور پھر قرآن کریم کو خدائے واحد کا کلام سمجھ کر
1188
Page 1197
جب بھی عمل کی کوششیں کرے گا تو گویا حقیقی توحید کو سمجھنے والا اور اس پر قائم ہونے والا ہو گیا اور
پھر قرآن کریم کی تعلیم پر مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق بھی ملے گی.تو انسان کو صرف اتنا ہی
نہیں سمجھ لینا چاہئے کہ میں نے سورۃ اخلاص پڑھ لی تو تین حصہ قرآن کریم پڑھ لیا.اس کا
مطلب یہ ہے کہ تم لوگ اس کو پڑھو اور پھر تو حید پر قائم ہوا اور اس پر عمل کرو.اسی طرح بعض روایات میں بعض اور آیات بھی ہیں جن کے بارے میں آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک حصہ ہے.یہ ایک چوتھائی حصہ ہے.تو اگر اسی کو لیا جائے تو
گویا ان چند آیتوں کو پڑھ کر لوگ کہیں گے کہ قرآن کریم مکمل ہو گیا.جبکہ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کی اس سے مراد یہ ہے کہ یہ ایسی باتیں ہیں جن پر تم لوگ عمل کرو اور پھر قرآن کریم پر
غور کرو، توحید کے قیام کی کوشش کرو تو تبھی تم قرآن کریم کو پڑھنے والے ہو گے.اور قرآن
کریم کیا ہے؟ قرآن کریم کی تعلیم توحید کے قیام کے لئے ہی ہے جس کے لئے ہر انسان کو
کوشش بھی کرنی چاہئے اور دعا بھی کرنی چاہئے.پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایک روایت ہے.آپ بیان کرتی ہیں کہ رسول
کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو ایک سریہ کا امیر بنا کر بھیجا.جنگ کے لئے روانہ کیا.جو اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتا تھا اور قراءت کا اختتام قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ پر کیا کرتا تھا.جب
صحابہ واپس آئے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا تو آپ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا.اس سے پوچھو کہ وہ کیوں ایسا کرتا ہے؟ صحابہ نے جب اس سے
پوچھا تو اس نے کہا اس لئے کہ یہ رحمان خدا کی صفت ہے.اس وجہ سے میں اس کو پڑھنا پسند
کرتا ہوں.اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اسے خبر دے دو کہ اللہ تعالیٰ بھی
اس سے محبت رکھتا ہے.( صحیح مسلم - کتاب صلوة المسافرین وقصرها ـ باب فضل قراءة قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ )
پھر اسی بارے میں بخاری میں حضرت انس کے حوالے سے ایک حدیث ہے.حضرت
انس سے روایت ہے کہ ایک انصاری آدمی مسجد قبا میں ان کی امامت کرایا کرتا تھا.وہ جب
1189
Page 1198
ان سورتوں میں سے جو نماز میں پڑھی جاتی ہیں کوئی سورۃ شروع کرتا تو پہلے قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ
یعنی سورۃ اخلاص پڑھتا.جب اسے پڑھ لیتا تو پھر اس کے ساتھ کوئی اور سورت پڑھتا اور ہر
رکعت میں ایسا ہی کرتا.اس کے ساتھیوں نے اس بارے میں اس سے بات کی اور کہا کہ تم
سورۃ اخلاص سے شروع کرتے ہو اور پھر نہیں سمجھتے یہ سورۃ تمہیں کافی ہوگئی بلکہ ایک اور سورت
بھی اس کے ساتھ پڑھتے ہو.یا تو تم اسی کو پڑھا کرو یا اس کو چھوڑ دو اور کوئی دوسری سورت
پڑھو.اس نے کہا کہ میں تو اسے ہر گز نہیں چھوڑوں گا.اگر تم پسند کرتے ہو کہ میں اسی طرح
تمہاری امامت کراؤں تو میں تمہارا امام رہوں گا.اور اگر تمہیں یہ پسند نہیں ہے تو میں تمہیں
چھوڑ دوں گا یعنی کہ امامت چھوڑ دوں گا.سورت کو نہیں چھوڑوں گا.وہ لوگ اس کو اپنے میں
سب سے زیادہ بہتر سمجھتے تھے.انہوں نے پسند نہ کیا کہ اس کے سوا کوئی اور ان کا امام ہو.جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے آپ کو اس واقعہ کی خبر دی.آپ
نے فرمایا اے فلاں جو بات تمہارے ساتھی تم سے کہتے ہیں تمہیں اس فعل سے کون سی بات
روکتی ہے.( یعنی کہ سورۃ اخلاص نہ پڑھو یا وہی پڑھو اور دوسری سورتیں نہ پڑھو.تو اکٹھی
پڑھنے کی کیا وجہ ہے؟ اور کیا وجہ ہے کہ تم نے یہ سورۃ ہر رکعت میں لازم کرلی ہے؟ اس نے
کہا یہ سورت مجھے بہت پیاری ہے.آپ نے فرمایا اس کی محبت نے تمہیں جنت میں داخل
کر دیا.(صحیح البخاری.کتاب الاذان باب الجمع بين السورتين في الركعة )
پھر حضرت ابی بن کعب بیان کرتے ہیں کہ جب مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
سے پوچھا کہ اپنے رب کا شجرہ نسب ہمیں بتائیں.اس پر اللہ تعالیٰ نے قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ
اللهُ الصَّمَدُ نازل فرمائی.پس صمد وہ ہے جو نہ کسی کا باپ ہے.نہ اس کا کوئی باپ ہے.کیونکہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو پیدا ہوئی مگر اس نے ضرور مرنا ہے.اور کوئی بھی ایسی چیز نہیں
جس نے مرنا ہے مگر اس کا ضرور کوئی نہ کوئی وارث ہوگا.جبکہ اللہ عز وجل نہ تو وفات پائے گا.نہ
1190
Page 1199
ہی اس کا کوئی وارث ہوگا.وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا اَحَدُ.کہا کہ اس کے مشابہ کوئی اور نہیں.اور نہ ہی کوئی اس جیسا ، اور نہ ہی اس کی مانند کوئی اور چیز ہے.( سنن الترمذی ابواب تفسیر القرآن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.باب ومن سورۃ الاخلاص )
اللہ وسلم.پھر اس بارے میں ایک جگہ حضرت ابوہریرۃ سے یوں روایت ملتی ہے.آپ بیان
کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے
سوال کرتے ہیں.یہانتک کہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا.یعنی کسی بھی چیز کو
اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا ؟ ( یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
زمانے میں بھی سوال ہوتے تھے.آج بھی یہ سوال بڑے اٹھائے جاتے ہیں.) آپ نے
فرمایا پس جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو تو قُلْ هُوَ الله احد کہو یہانتک کہ تم یہ سورت ختم کرلو.( یعنی سورۃ اخلاص پوری پڑھو.اس کے معنی پر غور کرو تو تمہیں پتا لگ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کو
پیدا کرنے والی کوئی چیز نہیں.وہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا.ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ
رہے گا.) فرمایا کہ پھر اس کو چاہئے کہ وہ شیطان سے پناہ طلب کرے تو وہ اس کو کوئی نقصان
نہیں پہنچا سکے گا.الابانة الكبرى لابن بطه باب ترك السؤال عما لا يُغْنِى وَالْبحث والتنقير)
حضرت ابوہریرہؓ بیان کرتے ہیں.میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آیا.آپ صلی
اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو قُلْ هُوَ اللهُ اَحَدُ اللهُ الصَّمَدُ پڑھتے ہوئے سنا تو رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی.میں نے پوچھا کیا چیز واجب ہو گئی؟ آپ نے
فرمایا جس اخلاص سے یہ پڑھ رہا ہے اس پر جنت واجب ہوگئی.( سنن الترمذی.ابواب تفسیر القرآن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.باب ومين سورۃ الاخلاص)
پھر حضرت سہیل بن سعد سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
آیا اور اپنی غربت کی شکایت کی.آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو اپنے گھر میں داخل ہو تو
اگر کوئی گھر میں ہو تو السّلامُ عَلَيْكُم کہا کرو.اور اگر کوئی نہ ہو تو پھر بھی السلام
1191
Page 1200
عَلَيْكُم کہہ دیا کرو.اپنے اوپر ہی سلامتی بھیجا کرو.والسلام تمہیں مل جائے گا اور ایک
دفعہ قُلْ هُوَ الله احد پڑھا کرو.تو اس آدمی نے ایسا ہی کیا یہانتک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو
اتن رزق عطا کیا کہ اس کے ہمسائے بھی اس سے فیضیاب ہونے لگے.( روح البیان لا سماعیل حقی بن مصطفیٰ زیر آیت سورۃ الاخلاص جلد 10 صفحہ 558.دارالکتب العلمیہ بیروت.2003ء)
یعنی اللہ تعالیٰ نے اس برکت سے اسے اتنا رزق عطا فرمایا کہ وہ ایک وقت ایسا تھا کہ خود
اس کو ہاتھ تنگ تھا.فاقے ہوتے تھے.اب اتنی کشائش پیدا ہوئی کہ وہ اپنے ہمسایوں کی بھی
مدد کیا کرتا تھا.پس جب انسان توحید کا سبق سیکھ لے اور اس پر عمل کرے اور خدا تعالیٰ کو تمام قدرتوں اور
طاقتوں کا مالک سمجھے تو پھر اللہ تعالیٰ بے انتہا نوازتا ہے.اللہ تعالیٰ اور جگہوں پر بھی فرماتا ہے
کہ وہ متقی کو ایسی ایسی جگہوں سے رزق دیتا ہے کہ جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتے.حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
آیا اور کہا کہ مجھے یہ سورۃ قُلْ هُوَ اللهُ اَحَد پسند ہے.تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا
اس سورت سے پیار تجھے جنت میں داخل کر دے گا.( مسند احمد بن حنبل.مسند المكثرين من الصحابة - مسند أنس بن مالک.حدیث 12432)
پھر حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ہر روز
پچاس مرتبہ قُلْ هُوَ اللهُ اَحَدٌ پڑھی اسے قیامت کے دن اس کی قبر سے پکارا جائے گا کہ کھڑا
ہو جا اور جنت میں داخل ہو جا.معجم الاوسط- باب الباء من اسمين يعقوب - حدیث 9446)
ابن دیلمی سے روایت ہے جو کہ نجاشی کی بہن کے بیٹے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
خدمت بھی کرتے رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز میں یا اس کے
علاوہ سومرتبہ قُلْ هُوَ اللهُ اَحَدُ پڑھا اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے آگ سے نجات فرض کر دی.لمعجم الكبير للطبرانی.جلد 18 صفحہ 331 - باب الفاء فیروز الدیلمی حدیث 852 - المكتبة الشاملة )
1192
Page 1201
پس یہ اہمیت ہے سورۃ اخلاص کی.اور جب ہم رات کو یہ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت
کوسامنے رکھتے ہوئے ہمیں یہ پڑھنی چاہئے.جب ہم کہیں کہ خدا تعالی آحد ہے تو ساتھ ہی
اس کے صمد ہونے کا مقام بھی اور مرتبہ بھی ہمارے سامنے آنا چاہئے.صمد وہ چیز ہے جو کسی کی
محتاج نہیں ہے اور کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے.کبھی بلاک ہونے والی نہیں ہے.حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو اس طرح بیان فرمایا ہے کہ :
صمد کے معنی ہیں کہ ”بجز اس کے تمام چیزیں ممکن الوجود اور هَا لِلةُ الذات ہیں.“
( براہین احمدیہ صفحہ 433- حاشیہ بحوالہ تفسیر حضرت مسیح موعود علیہ السلام جلد نمبر 4 صفحہ 756)
یعنی جو پیدا ہو سکتی ہیں اور ہوتی ہیں اور ختم ہونے والی ہیں انہیں فنا ہے.لیکن اللہ تعالیٰ کی
ذات ایسی ہے جو صد ہے.لوگ سمجھتے ہیں کہ صمد کا مطلب بے نیاز ہے.بے نیازی اس کی یہ
ہے کہ نہ وہ بلاک ہونے والا ہے، ختم ہونے والا ہے اور نہ اس جیسی کوئی چیز پیدا ہوسکتی ہے
پس یہ ہمارا خدا ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا.اور آپ فرماتے ہیں کہ خدا اپنی ذات اور صفات اور جلال میں ایک ہے.کوئی اس کا
شریک نہیں.سب اس کے حاجت مند ہیں.ذرہ ذرہ اسی سے زندگی پاتا ہے.وہ گل چیزوں
کے لئے مبدء فیض ہے.“ (یعنی دنیا کو فائدہ پہنچانے والی اور فیض دینے والی اسی کی ذات
ہے.اسی سے ہر فیض کے چشمے پھوٹتے ہیں ) اور آپ کسی سے فیضیاب نہیں ہوتا.“ ( یعنی
اس کو کوئی فیض پہنچانے والا نہیں ہے.وہی ہے جو دنیا کو فیض پہنچا رہا ہے.) وہ نہ کسی کا
بیٹا ہے اور نہ کسی کا باپ.اور کیونکر ہو کہ اس کا کوئی ہم ذات نہیں.قرآن نے بار بار خدا کا
کمال پیش کر کے اور اس کی عظمت دکھلا کے لوگوں کو تو جہ دلائی ہے کہ دیکھو ایسا خدا دلوں کو
مرغوب ہے.نہ کہ مردہ اور کمزور اور کم رحم اور کم قدرت.“
اسلامی اصول کی فلاسفی صفحہ 103.بحوالہ تفسیر حضرت مسیح موعود علیہ السلام جلد نمبر 4 صفحہ 757)
سورۃ اخلاص، سورۃ فلق اور سورۃ الناس کے نازل ہونے کے بارے میں حضرت عقبہ بن
عامر سے روایت ہے.وہ کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج رات ایسی
1193
Page 1202
آیات اتری ہیں کہ ان جیسی پہلے کبھی نہیں دیکھی گئیں.اور وہ یہ ہیں یعنی قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ
اور قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ اور قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ.( صحیح مسلم - کتاب صلوة المسافرین وقصرھا.باب فضل قراءة المعوذتين)
پھر احادیث میں تینوں قل پڑھنے کی اہمیت کے بارے میں روایت آتی ہے.حضرت
عقبہ بن عامر جہنی بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں ایک جنگی سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
سواری کی مہار پکڑ کر آگے آگے چل رہا تھا کہ آپ نے فرمایا اے عقبہ ! پڑھ.میں نے آپ
کی طرف کان لگایا تا کہ آپ جو فرمائیں وہ میں سن کر پڑھوں.پھر کچھ دیر کے بعد فرمایا اے
عقبہ پڑھ.میں پھر متوجہ ہوا کہ آپ کیا فرماتے ہیں.کیا پڑھوں میں؟ آپ نے تیسری مرتبہ
پھر یہی فرمایا تو میں نے عرض کیا.کیا پڑھوں؟ آپ نے فرمایا سورۃ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ.پھر
آپ نے آخر تک سورۃ پڑھی.پھر آپ نے سورۃ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ آخر تک پڑھی.میں بھی آپ کے ساتھ پڑھتا رہا.پھر آپ نے سورۃ قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ آخر تک
پڑھی.میں بھی آپ کے ساتھ پڑھتا رہا.پھر آپ نے فرمایا کسی شخص نے ان جیسی سورتوں یا
کلام کے ساتھ اللہ تعالی کی پناہ حاصل نہیں کی.“
( سنن النسائی کتاب الاستعاذة حديث 5430)
یعنی یہ ایسا کلام اور ایسی دعا ہے کہ جس سے انسان اللہ تعالی کی پناہ میں آجاتا ہے اور کبھی
ضائع نہیں ہوتا اور تمام شرور سے بچتا ہے.اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا اس سے بہتر اور کوئی ذریعہ
ہی نہیں.اور احادیث میں ایسی روایت ملتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس سے بہتر اللہ تعالیٰ کی
اور کوئی پناہ نہیں.پھر سورۃ فلق اور الٹاس کے بارے میں حضرت عقبہ بن عامر سے روایت ہے کہ میں ایک
سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی لگام پکڑے چل رہا تھا.آپ نے فرمایا اے
عقبہ ! کیا میں تجھے ایسی دو سورتیں نہ سکھاؤں جن کی قراءت انتہائی بہتر اور نفع بخش ہے.میں
نے عرض کیا کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ.تو آپ نے فرما یا قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ اور قُلْ
1194
Page 1203
اعُوذُ بِرَبّ الناس.اور جب آپ نے صبح کی نماز کے لئے پڑاؤ کیا تو آپ نے انہی کی
قراءت کی.یہی تلاوت کی.پھر جب آپ نے نماز ادا کر لی تو میری طرف متوجہ ہوئے اور
فرمایا اے عقبہ! تو کیسے دیکھتا ہے؟ ( شاید اس لحاظ سے بھی انہوں نے کہا ہو کہ بڑی چھوٹی
سورتیں آپ نے پڑھی ہیں.فرمایا ان میں تو سب کچھ ہے.)
( سنن ابوداؤد - ابواب الوتر.باب فی المعوذتین.حدیث 1462)
ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابوسعید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
جنات کی نظر سے اور انسانوں کی نظر سے پناہ مانگا کرتے تھے.جب معوذتین نازل ہوئیں تو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اختیار کر لیا اور باقی سب ترک کر دیا“.( سنن ابن ماجہ کتاب الطب باب من استرقى من العین حدیث 3511)
اس معاملے میں جو بھی دعائیں پہلے تھیں ان کو ختم کردیا اور پھر یہی پڑھا کرتے تھے.حضرت ابنِ عابس سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے
فرمایا کہ اے ابن عابس ! کیا میں پناہ لینے کے بارہ میں تجھے تعوذ کے سب سے افضل کلمات
کے بارے میں نہ بتاؤں؟.بہترین پناہ کس طرح کی ہے جن سے پناہ مانگنے والا پناہ مانگا
کرتے ہیں.میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا وہ سورتیں ہیں سورۃ
فلق اور سورۃ ناس.( مسند احمد بن حنبل.جلد 5 صفحہ 322- مسند المگیین.حدیث ابن عابس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث 15527)
پھر آخری دوسورتوں کی اہمیت بیان کرتے ہوئے ایک صحابی کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک
مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر میں تھے.چونکہ سواری کے جانور کم تھے اس
لئے لوگ باری باری سوار ہوتے تھے.ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے
اترنے کی باری تھی.رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے میرے قریب آئے اور میرے
کندھوں پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ پڑھو.میں نے یہ کلمہ پڑھ لیا.اسی طرح
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورۃ مکمل پڑھی اور میں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
1195
Page 1204
اسے پڑھ لیا.پھر اسی طرح اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاس پڑھنے کے لئے فرمایا اور پوری سورۃ پڑھی
جسے میں نے بھی پڑھ لیا.پھر آپ نے فرمایا جب نماز پڑھا کرو تو یہ دونوں سورتیں نماز میں
پڑھ لیا کرو.( مسند احمد بن حنبل - جلد 6 صفحہ 918 - اوّل مسند البصر بین.حدیث رجل عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث 21025)
عقبہ بن عامر جہنی سے روایت ہے کہ میں ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
تھا.جب فجر طلوع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کہی اور اقامت کہی.پھر مجھے اپنے
دائیں جانب کھڑا کیا.پھر آپ نے معوذتین کے ساتھ قراءت کی.جب آپ نماز سے
فارغ ہوئے تو فرمایا تو نے کیسا دیکھا ؟ ( وہ پہلے والی روایت سے ملتا ہے.) میں نے عرض کی
که تحقیق میں نے دیکھ لیا یا رسول اللہ ! تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی تو سوئے اور
جب بھی اٹھے تو یہ دونوں سورتیں پڑھا کر.المصنف فی الاحادیث والآثار از ابوبکر بن ابی شیبۃ جلد 1 صفحہ 403 - کتاب الصلوات من كان يخفف القراءة في السفر -
حدیث 3688)
پس یہ اہمیت ہے ان سورتوں کی اور اس زمانے میں ذاتی طور پر ہماری روحانی ترقی اور
شیطان کے حملوں سے بچنے کے لئے اور جماعتی طور پر اسلام کے خلاف جو سازشیں ہورہی ہیں
ان سے بچنے کے لئے ان کے پڑھنے کی اہمیت اور بھی بڑھ گئی ہے.آجکل اسلام کے خلاف
ایک طرف اسلام مخالف طاقتوں کی بڑی ہوشیاری سے کوششیں جاری ہیں تو دوسری طرف نام
نہاد مسلمان علماء اور مسلمان لیڈروں نے ایک ایسی صورتحال پیدا کر دی ہے جہاں فتنہ وفساد پیدا
ہو چکا ہے.مسلمان علماء مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف عامۃ المسلمین کو بھڑکا کر شیطانی قوتوں
کو بھی اور موقع دے رہے ہیں کہ ان کے ہاتھ مضبوط ہوں.اسی طرح دہریت ہے تو وہ بھی
آجکل اپنے زوروں پر ہے.سورۃ فلق کے حوالے سے اس بات کو بیان فرماتے ہوئے
حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ وضاحت فرماتے ہیں کہ
تم جو...مسیح موعود کے دشمنوں کا نشانہ بنو گے یوں دعا مانگا کرو کہ میں مخلوق کے شر
1196
Page 1205
سے جو اندرونی اور بیرونی دشمن ہیں اس خدا کی پناہ مانگتا ہوں جو صبح کا مالک ہے.یعنی روشنی کا
ظاہر کرنا اس کے اختیار میں ہے.( یہ روشنی روحانی روشنی ہے جو مسیح موعود کے آنے سے ظاہر
ہوتی ہے ) اور میں اس اندھیری رات کے شر سے جو......انکار
مسیح موعود کے فتنے کی رات
ہے خدا کی پناہ مانگتا ہوں“.(تحفہ گولڑویہ صفحہ 78.حوالہ تفسیر حضرت مسیح موعود علیہ السلام جلد نمبر 4 صفحہ 762)
ان میں ایک تو اسلام دشمن لوگ ہیں جو اسلام کی تعلیم پر اعتراض کرتے ہیں اور دوسرے
علماء اسلام ہیں جو اپنی غلطی کو چھوڑ نا نہیں چاہتے اور مسیح موعود کے خلاف لوگوں کو بھڑکانے میں
مصروف ہیں.جن میں پاکستان کے علماء ہم دیکھتے ہیں کہ سر فہرست ہیں.پس ایسے حالات میں پاکستان میں تو احمدیوں کو خاص طور پر اس سنت کو جاری کرنے کی
ضرورت ہے.حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ سورۃ فلق میں جو شَرِ غَاسِقٍ إِذَا
وَقَبَ کہا گیا ہے اس میں اندھیری رات کے شر کے فتنہ سے بچنے کی دعا ہے.غاسق کہتے
ہیں رات کو اور وقب کا مطلب ہے اندھیرے اور ظلمت کا چھا جانا اور یہ اندھیری رات کا فتنہ
مسیح موعود کے انکار کے فتنہ کی شب تار ہے جس سے پناہ مانگی گئی ہے.افسوس ہے مسلمانوں کی حالت پر کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک دعا سکھائی اور روشنی کے بعد
اندھیرے اور ظلمات کے فتنہ سے بچنے کے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان
دعاؤں کو بلا ناغہ روزانہ پڑھا کرو تا کہ توحید پر بھی قائم رہو اور اندھیروں اور ظلمات کے فتنوں
سے بھی بچو لیکن مسلمانوں نے اس کی پرواہ نہیں کی.مسلمان تو اکثر ان
فتنوں میں ڈوب رہے
ہیں اور اسی وجہ سے آج دنیا میں غیر مسلموں کو مسلمانوں پر اعتراض کرنے کا موقع مل رہا ہے.بہر حال مسلمانوں کی یہ حالت ہمیں توجہ دلاتی ہے کہ ان سورتوں پر غور کر کے پڑھیں تا کہ ان
اندھیروں سے ہم بچ سکیں.شَرِ النَّفْتِ فِي الْعُقَدِ سے بھی اللہ تعالی کی پناہ میں رہیں.جو
1197
Page 1206
نفقت کے شر ہیں ، جو گر ہیں ہیں ان سے بھی ہم اللہ تعالی کی پناہ میں رہیں.یعنی ان لوگوں سے
جو اسلام اور احمدیت کے خلاف بڑے طریقے سے لوگوں کے دلوں میں بغض و کینہ پیدا کر رہے
ہیں.اور اس میں جیسا کہ میں نے کہا غیر مسلم اور نام نہاد علماء دونوں شامل ہیں.ایک تو دین
کے خلاف ہونے کی وجہ سے اپنی کارروائیاں کر رہے ہیں.غیر مسلم اسلام کے خلاف ہونے
کی وجہ سے کارروائیاں کر رہے ہیں.اور دوسرے دین کے نام پر اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے
کے خلاف لوگوں کو بھڑکا کر یہ کارروائیاں کر رہے ہیں.اور دونوں ہی اس زمرہ میں شامل ہیں
جن کے بارے میں فرمایا کہ وَمِنْ شَرِّ النَّقْتُتِ فِي الْعُقَدِ
پھر سورۃ الناس میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور مالکیت اور حقیقی معبود ہونے کا بیان ہے.یہ
بیان کر کے اس کی پناہ میں آنے اور شیطان کے وسوسے سے بچنے کی دعا کی ہے.آجکل
دہریت اور دنیا کا بھی بڑا زور ہے اور دنیاداری نے اس قدر معاشرے میں عمومی طور پر اپنے
پنجے گاڑ دیئے ہیں کہ بعض نوجوان اس سے متاثر ہو جاتے ہیں.پس یہ دعا ئیں جب ہم اپنے پر
پھونکیں تو ساتھ ہی اپنے بچوں پر بھی پھونکیں تا کہ ہر قسم کے شرور سے ہماری نسلیں بھی محفوظ رہیں
اور دین پر قائم رہنے والی اور خدا تعالیٰ کی وحدانیت کو سمجھنے والی ہوں.اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم میں سے ہر ایک ان سورتوں کے مضمون کو سمجھتے ہوئے آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا ہو.خدا تعالیٰ کی وحدانیت کا مضمون ہم پر واضح ہو.اس کے علاوہ کسی اور کے آگے ہم جھکنے والے نہ ہوں.اسی کوسب طاقتوں کا سر چشمہ سمجھیں.نہ
صرف دل میں بلکہ ہر عمل سے اسے ثابت کریں کہ اللہ تعالیٰ ہی سب طاقتوں کا سرچشمہ ہے.ہر روشنی کا منبع ہے.اور ہر فیض کا دینے والا ہے مخلوق کے شر سے بچنے کے لئے اللہ تعالیٰ کے
آگے جھکیں بجائے اس کے کہ مخلوق سے امید رکھیں.حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مان کر ہم
نے جس روشنی کو حاصل کر لیا ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی نور کا پر تو ہے اللہ تعالیٰ
سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر ہمیشہ قائم رکھے اور
کبھی ہم اندھیروں اور ظلمات میں بھٹکنے
1198
Page 1207
والے نہ ہوں.اور اللہ تعالیٰ کے انعاموں میں سے جو خلافت کا انعام ہمیں ملا ہے اس سے ہم
ہمیشہ وابستہ رہیں.ہر نقصان پہنچانے والے کے شر سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے
چاہے وہ دینی شر ہے یا دنیاوی شر ہے.ہر حاسد کے حسد سے اور اس کے نقصانات سے اللہ
تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے.ہمیشہ خدا تعالیٰ کو ہی اپنا رب اور اپنا پالنے والا سمجھ کر ہم اس کی پناہ میں
رہیں.سب بادشاہوں سے افضل خدا تعالیٰ کو سمجھیں اور اس کی مالکیت پر کامل یقین رکھنے
والے ہوں.اس معبود حقیقی کی عبادت کے بھی حق ادا کرتے ہوئے ہر دم اس کی پناہ میں آنے
کی کوشش کریں.وسوسے پیدا کرنے والوں کے شر سے بچیں.اس سے اللہ تعالی کی پناہ
میں آئیں.اپنے دلوں کو بھی ہر وسوسے سے پاک رکھنے کی کوشش رکھیں اور اس کے لئے
اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے رہیں.اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہم باقاعدگی سے سونے سے پہلے یہ آیات پڑھ
کر، ان دعاؤں کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اپنے پر پھونکنے والے
ہوں.اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے.خطبہ جمعہ حضرت خلیفتہ امسیح الخامس اید « اللہ تعالی فرمودہ 16 فروری2018ء)
1199