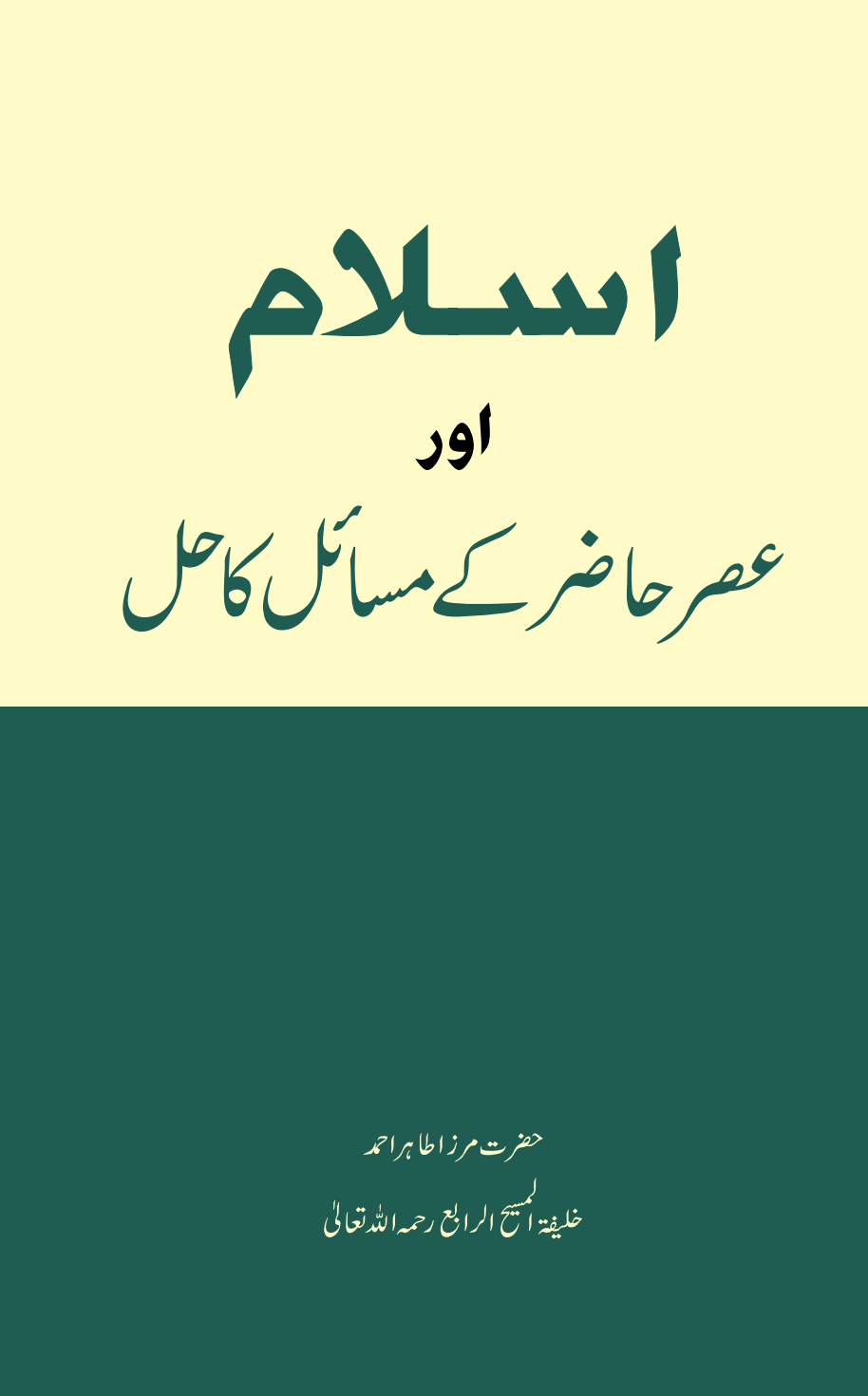Complete Text of IslamAurAsreHazir
Content sourced fromAlislam.org
Page 1
اسلام
اور
عصر حاضر کے مسائل کاحل
حضرت مرزا طاہر احمد
خلیفة المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ
Page 2
عرض ناشر
قرآن کریم کی ہر سورة بسم الله الرحمن الرحیم سے شروع ہوتی ہے
سوائے سورۃ التوبہ کے.ہمارے نزدیک یہ قرآن کریم کا حصہ ہے اس لئے سورۃ کی پہلی
آیت شمار ہوتی ہے.تاہم قرآن کریم کو شائع کرنے والے بعض ناشرین بسم اللہ الرحمٰن
الرحیم کو سورۃ کی پہلی آیت شمار نہیں کرتے.اس لئے اگر کسی قاری کو اس کتاب میں
درج کسی آیت کریمہ کا حوالہ نہ ملے تو دیئے گئے آیت نمبر میں سے ایک منہا کرلیا جائے.مثال کے طور پر سورۃ البقرہ آیت نمبر ۲۸۶ جو اس کتاب میں درج ہے قرآن کریم کے بعض
نسخوں میں اس کا نمبر ۲۸۵ ہوگا.عربی متن کے ترجمہ میں جہاں ضروری سمجھا گیا ہے وہاں
زائد الفاظ بھی شامل کئے گئے ہیں تا کہ مفہوم واضح ہو جائے.ان زائد الفاظ اور اصل ترجمہ کی
طرز تحریر میں کوئی فرق نہیں ہے.احادیث کی کتب کے چونکہ بہت سے ایڈیشن موجود ہیں
اس لئے حوالہ دیتے ہوئے صرف کتاب کا نام دیا گیا ہے اختصار کی خاطر جلد اور باب کا حوالہ
نہیں دیا گیا.
Page 4
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّي عَلَى رَسُوْلِهِ الْكَرِيمِ
تعارف
جماعت احمدیہ کی بنیاد حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود
و مہدی معہود علیہ السلام نے ۱۸۸۹ء میں رکھی تھی.آپ نے خدا تعالیٰ سے خبر پا کر یہ دعویٰ
فرمایا کہ آپ ہی وہ موعود مسیح اور مہدی ہیں جن کی آخری زمانہ میں بعثت کی پیشگوئیاں دنیا
کے سبھی عظیم مذاہب کی کتب مقدسہ میں موجود ہیں.جماعت احمدیہ گزشتہ سو سال سے زائد عرصہ سے دنیا بھر میں اشاعت اسلام کی
جدو جہد میں مصروف ہے.حضرت مرزا طاہر احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ۱۹۸۲ء میں سیدنا
حضرت مسیح موعود علیہ السلام بانی جماعت احمدیہ کے چوتھے خلیفہ منتخب ہوئے.۱۹۸۴ء میں
جب پاکستان میں جماعت احمدیہ کی مذہبی آزادی پر پابندیاں عائد کر دی گئیں اور آپ کے
لئے پاکستان میں رہتے ہوئے اپنی تبلیغی اور تربیتی ذمہ داریوں کو ادا کرنا ناممکن بنا دیا گیا تو
آپ لنڈن تشریف لے گئے.حضرت مرزا طاہر احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ دینی اور دنیوی علوم کا ایک سمندر
تھے.آپ نے مذہبی موضوعات پر ہزاروں خطابات ارشاد فرمائے.عصر حاضر کے نہایت
اہم مسائل کے متعلق ان گنت سوالات کے جوابات دئے.اب بھی آپ کے خطابات اور
مجالس سوال و جواب کو مسلم ٹیلیویژن احمدیہ انٹر نیشنل پر دنیا بھر میں دیکھا اور سنا جا سکتا ہے.آپ کی تصنیف ”مذہب کے نام پر خون“ کا ترجمہ کئی زبانوں میں شائع ہو چکا ہے.انگریزی زبان میں آپ کی ایک عظیم اور معرکۃ الآرا اور عہد ساز تصنیف ,Revelation"
"Rationality, Knowledge and Truth یعنی الہام، عقل، علم اور سچائی“
۱۹۹۸ میں لنڈن سے شائع ہوئی.iii
Page 5
۱۹۸۹ء میں جماعت احمدیہ کے قیام کی صد سالہ جوبلی منائی گئی.اس تقریب کے
موقع پر ۲۴ فروری ۱۹۹۰ ء کو لندن کے کوئین ایلیز بیتھ کانفرنس سینٹر میں اسلام اور
عصر حاضر کے مسائل کا حل کے موضوع پر امام جماعت احمدیہ حضرت مرزا طاہر احمد صاحب
رحمہ اللہ تعالیٰ نے انگریزی زبان میں ایک تقریر فرمائی.اس تقریر کو سننے کے لئے دانشور
طبقوں سے تعلق رکھنے والے آٹھ صد معزز مہمان تشریف لائے.ان میں سیاست دان،
صحافی، پروفیسر صاحبان، اساتذہ کرام مذہبی علوم کے ماہرین، عربی دان اور دیگر
شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے معزز خواتین و حضرات شامل تھے.اس وقت کے
امیر جماعت ہائے احمد یہ برطانیہ مکرم و محترم آفتاب احمد خان صاحب (مرحوم) نے مہمانوں
کو خوش آمدید کہا، مکرم ایڈورڈ مارٹیمر (Edward Mortimer) نے اس تقریب کی
صدارت فرمائی جبکہ حضور رحمہ اللہ تعالیٰ کے خطاب کے بعد ممبر پارلیمنٹ مکرم ہیوگو سمرسن
(Hugo Summerson) نے جذبات تشکر کا اظہار فرمایا.بعد ازاں سوال و جواب کی
ایک مختصر مجلس منعقد ہوئی.اس نوعیت کے پبلک اجتماعات میں بالعموم تقاریر کیلئے جتنا وقت مختص کیا جاتا ہے
اس میں ایسے وسیع مضمون کو کما حقہ بیان کرنا ممکن نہیں ہوتا لیکن حضرت امام جماعت احمدیہ
رحمہ اللہ تعالیٰ نے مختصر وقت کے باوجود اس موضوع پر سیر حاصل بحث فرمائی ہے.یہ خطاب Islam's Response to Contemporary"
"Issues کے نام سے ۱۹۹۲ ء میں انگریزی میں شائع ہو چکا ہے.اب اس کا اردو ترجمہ
جو
کی
زیر نگرانی کیا ہے احباب کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے.اس کی پروف ریڈنگ میں
مکرم منیر الدین شمس صاحب ایڈیشنل وکیل التصنیف نے بہت محنت سے کام کیا اور کتاب
کی ترتیب میں بہتری کے سلسلہ میں مفید مشورے دئے.اسی طرح
iv
Page 6
نے بھی پروف ریڈنگ میں مدد کی
نے
کمپیوٹر پر غلطیوں کی اصلاح میں بہت وقت دیا.اسی طرح دیگر احباب نے بھی مختلف امور
میں مدد کی.اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے.آمین
اس خطاب میں جن امور پر حضور انور رحمہ اللہ تعالیٰ نے گفتگو فرمائی وقت گزرنے
کے ساتھ ان کی اہمیت اور بھی واضح ہوتی چلی جا رہی ہے.حضرت امام جماعت احمدیہ
رحمہ اللہ تعالیٰ کی دُور بین نگاہ نے مستقبل کے جن امکانات اور خدشات کی نشان دہی فرمائی
تھی وہ حیرت انگیز طور پر سچ ثابت ہو رہے ہیں.مثال کے طور پر اشتراکیت کے زوال کے
بعد مشرقی یورپ کے ممالک میں عظیم الشان تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں.اقوام متحدہ
بین الاقوامی معاملات میں وہی کردار ادا کر رہی ہے جس کی طرف حضور نے اشارہ فرمایا تھا.برطانیہ میں شرح سود کی پالیسی کا نتیجہ اقتصادی بدحالی کی صورت میں سامنے آیا ہے.یہ تمام
امور اور در حقیقت ان کے علاوہ بہت سے امور اس خطاب میں قبل از وقت پوری وضاحت
کے ساتھ بیان کر دیئے گئے تھے.حضرت امام جماعت احمد یہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے ۱۹۹۰ ء کے
آغاز میں جب یہ خطاب فرمایا تھا اس وقت ابھی ان تمام تبدیلیوں کے آثار دنیا کے افق پر
ظاہر نہیں ہوئے تھے.بہت کم ایسا ہوا ہے کہ قبل از وقت دنیا کو اس قدر واضح انتباہ کر دیا گیا
ہو.حضور رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ خطاب جس پیغام پر مشتمل ہے وہ دائی اہمیت کا حامل ہے اور اس
کا تعلق امن عالم کے مستقبل سے ہے.جو پیش خبریاں اس خطاب میں موجود ہیں اگر ان میں
سے اکثر کو آئندہ رونما ہونے والے واقعات نے سچ کر دکھایا جیسا کہ بعض سچ ثابت بھی ہو
چکی ہیں تو پھر عالمی رہنماؤں کو چاہئے کہ وہ اس پیغام کی اہمیت کو سمجھیں اور نظام دنیا کی تشکیل
نوکرتے ہوئے اس سے بھر پور فائدہ اٹھائیں.خدا کرے کہ ایسا ہی ہو.آمین.V
Page 8
3
7
10
11
13
27
28
30
36
39
41
22222222
فہرست مضامین
ا.مذاہب عالم کے مابین امن و آشتی اور ہم آہنگی
مذہبی اقدار کو فضول اور غیر ضروری سمجھ لیا گیا ہے
انبیاء ہر قوم میں مبعوث ہوتے رہے ہیں
بلحاظ منصب تمام انبیاء برابر ہیں
کیا منصب میں برابری کے باوجود انبیاء کے مقام ومرتبہ میں فرق ہو سکتا ہے؟
نجات پر کسی ایک مذہب کی اجارہ داری نہیں ہوسکتی
مذاہب کے مابین ہم آہنگی اور باہمی احترام کا فروغ
مذہب کے عالمگیر ہونے کا نظریہ
اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے
اشاعت دین کے ذرائع.جبر کی بکلی نفی
کون سا مذ ہب باقی رہے گا؟ ( بقائے اصلح )
آزادی تقریر
آزادی کی حدود
مذہبی نقدس کی پامالی
مذاہب کا باہمی تعاون
حاصل بحث
۲.معاشرتی امن
عصر حاضر کا معاشرتی نظام
دو قسم کے معاشرتی ماحول
مادہ پرست معاشرہ کا انجام
43
44
52
53
61
65
70
71
vii
Page 9
73
77
79
94
98
100
104
105
110
111
122
127
130
132
134
135
138
142
157
161
164
165
166
حیات بعد الموت کا انکار
مادہ پرست معاشرہ کی چار خصوصیات
اعمال کی جوابدہی کا تصور
اسلامی معاشرہ کا مخصوص ماحول
اسلامی معاشرہ کے بنیادی اصول
عفت اور پاکدامنی
پر دہ اور اس کی حقیقت
حقوق نسواں کے ایک نئے دور کا آغاز
عورتوں کے لئے مساوی حقوق
تعدد ازدواج
عمر رسیدہ افراد کی دیکھ بھال
مستقبل کی نسلیں
بے مقصد اور فضول مشاغل کی حوصلہ شکنی
خواہشات پر قابو پانا
عہد و پیمان اور معاہدات کا احترام
برائی کا خاتمہ.ایک اجتماعی ذمہ داری
اوامر نواہی
اسلام نسل پرستی کورڈ کرتا ہے
۳.معاشرتی اقتصادی امن
سرمایہ دارانہ نظام سوشلزم اور اسلام میں معاشی انصاف کا تصور
تنگ دستی کے باوجود اعلیٰ مقاصد کے لئے خرچ کرنا
غرباء کے لئے خرچ کرنا
شکر گزاری کا جذبہ
viii
Page 10
170
172
175
176
176
177
179
180
181
186
186
191
195
195
195
197
298
199
203
205
209
209
214
نیکی کے اجر کی توقع کسی انسان سے نہ رکھنا
بھیک مانگنا
مالی قربانی کے لئے طیب مال کی شرط
خدا کے راستہ میں اعلانیہ اور پوشیدہ خرچ
معاشرتی ذمہ داریاں
تاریخ اسلام کا ایک واقعہ
خدا کی عطا کردہ سب نعمتوں میں سے خرچ کرنا
خدمت خلق
شراب نوشی اور جوئے کی ممانعت
شراب نوشی کے باعث ہونے والی اموات
شراب نوشی کے باعث ہونے والے سالانہ اقتصادی نقصانات
۴.اقتصادی امن
سرمایہ دارانہ نظام، اشتراکیت اور اسلام کا اقتصادی فلسفہ
سرمایہ دارانہ نظام
سائینٹفک سوشلزم
اسلامی نظریہ
سرمایہ دارانہ معاشرہ کی چارخصوصیات
دنیا کا بدلتا ہوا اقتصادی نظام
اسلام کا اقتصادی نظام
زكوة
سود کی ممانعت
برطانیہ میں شرح سود کا مسئلہ
سود کے دیگر نقصانات
ix
Page 11
221
223
226
227
228
229
229
234
236
237
237
240
245
257
253
257
258
262
264
265
266
269
271
X
سود.امن کے لئے ایک خطرہ
دولت کے انبار لگانے کی ممانعت
سادہ طرز زندگی
شادی و بیاہ کے اخراجات
غرباء کی دعوت قبول کرنا
کھانے پینے میں اعتدال
قرض کا لین دین
معاشی طبقاتی فرق
اسلام کا قانون وراثت
رشوت کی ممانعت
تجارتی ضابطہ اخلاق
بنیادی ضروریات زندگی
عبادت معاشرتی وحدت کا ایک ذریعہ
عالمی ذمہ داریاں
۵.قومی اور بین الاقوامی سیاسی امن
اسلام کسی سیاسی نظام کو کلیۂ رد نہیں کرتا
بادشاہت
جمہوریت کیا ہے؟
جمہوریت کا اسلامی تصور
اسلامی جمہوریت کے دوستون
مشاورت
اسلامی حکومت کیا ہے
ملائیت
Page 12
274
276
281
285
287
295
299
302
303
305
307
307
308
313
کیا مذہب کا وفادار مملکت کا غدار ہوسکتا ہے؟
کیا صرف مذہب ہی کو قانون سازی کا حق حاصل ہے؟
اسلام اور ریاست
بین الاقوامی تعلقات کی بنیاد کامل انصاف پر ہے
اقوام متحدہ کا کردار
۶.انفرادی امن
مسابقت في الخيرات
اعزہ و اقرباء کے ساتھ محبت
خدمت خلق
رضائے باری تعالیٰ کا حصول
لوگوں کے دکھ درد سے ہمیشہ باخبر رہنا
محبت و شفقت کا وسیع دائرہ
تخلیق انسانی کا مقصد
اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کوئی امن نصیب نہیں ہو سکتا.xi
Page 13
60-9
و و یک =
909-690-
أشْهَدُ أَنْ لَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَريكَ لَهُ وَاشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُوله -
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطنِ الرَّحِيم - بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْن الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ O مُلِكِ يَوْمِ الدِّينِ 0
إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِيْن 0 اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيم 0
صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِينَ
صدر گرامی قدر جناب ایڈورڈ مار ٹیمر صاحب، مہمانان کرام و خواتین و حضرات!
میں آپ سب صاحبان علم و دانش کا شکر گزار ہوں کہ آپ آج کی تقریب میں
شمولیت کے لئے تشریف لائے.آج میں جس موضوع پر خطاب کرنا چاہتا ہوں وہ
میرے لئے ایک چیلنج کی حیثیت رکھتا ہے.یہ ایک بہت وسیع اور ہمہ جہت
مضمون
ہے.مجھے ڈر ہے کہ شاید اس محدود وقت میں اس موضوع کا حق ادا نہ ہو سکے.تاہم
میں دو بنیادی سوالات اٹھا کر اپنے اس خطاب کا آغاز کرتا ہوں.پہلا سوال تو یہ ہے کہ اس جدید دور کے وہ کون سے مسائل ہیں جو ہمارے لئے
چیلنج بنے ہوئے ہیں.اور دوسرا یہ کہ مذہب ان حالات میں ہماری کیا راہنمائی کرسکتا ہے؟
دور حاضر کا سب سے اہم مسئلہ امن و آشتی کا فقدان ہے.مادی ترقی کے لحاظ
سے بحیثیت مجموعی آج کا انسان بہت بلند مقام تک جا پہنچا ہے.یہ وہ ہمہ جہت ترقی
ہے جو زندگی کے تمام شعبوں میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی حیرت انگیز ترقی کے باعث
ممکن ہوئی ہے.اس سائنسی ترقی کے ثمرات اس دور میں بالخصوص ان ممالک کے
حصہ میں آئے ہیں جو پہلی اور دوسری دنیا کے ممالک کہلاتے ہیں.تاہم تیسری دنیا
کے ممالک نے بھی ایک حد تک ان سے فائدہ اٹھایا ہے.یہاں تک کہ سائنسی ترقی
1
Page 14
کی روشنی دنیا کے ان تاریک ترین خطوں تک بھی جا پہنچی ہے جہاں آج بھی لوگ
قدیم زمانے جیسے حالات میں زندگی بسر کر رہے ہیں مگر ان تمام ترقیات کے باوجود
آج کا انسان حقیقی خوشی اور اطمینان سے محروم ہے.بے چینی اضطراب اور خوف کی
کیفیت بڑھتی جا رہی ہے.ایک غیر یقینی مستقبل کے مہیب سائے گہرے ہوتے
جارہے ہیں.ماضی سے جو کچھ انسان کو ورثہ میں ملا ہے اس پر سے اعتماد اٹھ رہا
ہے.بے اطمینانی ہے کہ بڑھتی ہی چلی جارہی ہے.اسلام کے لغوی معنی امین کے ہیں.اگر دیکھا جائے تو اس ایک لفظ میں اسلام کی
جملہ تعلیمات کمال خوبصورتی اور جامعیت کے ساتھ جھلکتی نظر آتی ہیں.بلاشبہ اسلام
امن کا مذہب ہے.اس کی تعلیمات انسانی آرزوؤں اور دلچسپیوں کے سب دائروں
میں امن کی ضمانت دیتی ہیں.چنانچہ آج کے خطاب کے لئے میں نے بعض ایسے امور کو منتخب کیا ہے جن کے
بارہ میں دنیا کو راہنمائی کی اشد ضرورت ہے اور وہ امور یہ ہیں:
ا.مذاہب عالم کے مابین امن و آشتی اور ہم آہنگی.۲.معاشرتی امن.۳.معاشرتی اقتصادی امن.-۴- اقتصادی امن.۵.قومی اور بین الاقوامی سیاسی امن.۶.انفرادی امن.2
Page 15
مذاہب عالم کے مابین امن و آشتی اور ہم آہنگی
مذہبی اقدار کو فضول اور غیر ضروری سمجھ لیا گیا ہے
انبیاء ہر قوم میں معبوث ہوتے رہے ہیں
بلحاظ منصب تمام انبیاء برابر ہیں
حملہ کیا منصب میں برابری کے باوجو دمرتبہ اور مقام میں فرق ہو
سکتا ہے؟
نجات پر کسی ایک مذہب کی اجارہ داری نہیں ہو سکتی
مذاہب کے مابین ہم آہنگی اور باہمی احترام کا فروغ
مذاہب کے عالمگیر ہونے کا نظریہ
اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے...اشاعت دینی کے ذرائع : جبر کی بکلی نفی
کونسامنہ ہب باقی رہے گا ؟ ( بقائے صلح )
آزادی تقریر....آزادی کی حدود
ا...مذہبی تقدس کی پامالی
حمد مذاہب کا باہمی تعاون......حاصل بحث
3
Page 17
280
وید
إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ ۖ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَ إِنْ مِنْ أُمَةٍ
280
إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيره
(سورۃ فاطر آیات نمبر ۲۵،۲۴)
ترجمہ.تو تو محض ایک ڈرانے والا ہے.یقیناً ہم نے تجھے حق
کے ساتھ بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے.اور کوئی امت نہیں مگر ضرور
اس میں کوئی ڈرانے والا گزرا ہے.إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِدُونَ وَالنَّصْرَى مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَO
(سورۃ المائدہ آیت نمبر ۷۰)
ترجمہ.یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور
صابی اور نصرانی، جو بھی اللہ پر ایمان لایا اور یوم آخر پر اور نیک
عمل بجالایا ان پر کوئی خوف نہیں اور وہ کوئی غم نہیں کریں گے.LO
5
Page 19
مذہبی اقدار کو فضول اور غیر ضروری سمجھ لیا گیا ہے
آج کی مذہبی دنیا ایک عجیب تضاد کا شکار ہو چکی ہے.ایک طرف تو بالعموم
مذہب سے بیگانگی بڑھ رہی ہے مگر دوسری طرف بعض پہلوؤں سے مذہب کی گرفت
مضبوط ہوتی چلی جا رہی ہے.لوگوں کے دل و دماغ اور عملی زندگی پر مذہب کا حقیقی
اثر کمزور پڑرہا ہے لیکن کٹر مذہبی عقائد کو از سر نو اختیار کیا جا رہا ہے.رواداری کا
فقدان ہے اور مذہبی تشدد پسندی عام ہو رہی ہے.دوسری طرف اگر دنیا کے عام
اخلاقی معیار کو دیکھا جائے تو صاف نظر آتا ہے کہ مذہب پسپا ہو رہا ہے.جرائم تیزی
سے بڑھ رہے ہیں.صداقت دنیا سے اٹھتی جا رہی ہے.عدل و انصاف نا پید ہوتا
دکھائی دے رہا ہے.فرد معاشرہ کی طرف سے عائد ذمہ داریوں کو نظر انداز کر رہا
ہے.خود غرضی پر مبنی انفرادیت پسندی زور پکڑتی جا رہی ہے.یہ معاشرتی برائیاں
ان ممالک میں بھی عام ہیں جو مذہبی ہونے کا دعوی کرتے ہیں.یہ اور ایسی دیگر بہت
سی برائیاں اس اخلاقی انحطاط کی مظہر ہیں جواب دنیا کے نظام کا حصہ بن چکی ہیں.اگر اخلاقی اقدار ہی مذہب کی جان ہیں تو ان اقدار کے رفتہ رفتہ اٹھ جانے کا ناگزیر
نتیجہ یہی ہے کہ مذہب کے ظاہری ڈھانچے اور جسم کی تعمیر نو تو ہو رہی ہے مگر روح اس
جسم سے پرواز کر چکی ہے.پس حقیقت یہی ہے کہ مذہب کا یہ نام نہاد احیاء اپنے
ندر حقیقی زندگی کی کوئی علامت نہیں رکھتا.یہ تو ایسے ہی ہے جیسے جنوبی افریقہ کے
بعض قبائل میں جادو کے زور سے لاش کو چلتا پھرتا دکھائے جانے کا تصور پایا جاتا
اندر
ہے.اس کے ساتھ ساتھ بعض جگہ طویل جمود کے باعث اور کسی ولولہ انگیز ترقی کے نہ
ہونے کی وجہ سے مذہب کی طرف مائل لوگوں میں ایک قسم کی بوریت اور اکتاہٹ
7
Page 20
پیدا ہو رہی ہے.جن معجزات کی توقع وہ لگائے بیٹھے ہیں وہ پوری ہوتی نظر نہیں
آتی.وہ چاہتے ہیں کہ واقعات عالم کسی مافوق الفطرت طاقت کے ذریعہ ان کی
مرضی کے مطابق تبدیل ہو جائیں.مگر ایسا عجیب و غریب عمل حقیقت کی دنیا میں انہیں
کہیں دکھائی نہیں دیتا.وہ عجیب و غریب پیشگوئیوں کو پورا ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں
تا کہ ان کا اعتقاد بڑھے مگر ان کی کوئی خواہش حقیقت کا روپ دھارتی نظر نہیں آتی.یہی وہ لوگ ہیں جو نت نئے مذہبی گروہوں (Cults) کے قیام میں مددگار ثابت
ہوتے ہیں.ان کی مایوسیاں ایسے گروہوں کی نشوونما کے لئے بڑی سودمند ہوتی
ہیں.دراصل نئی چیز کی تلاش اس خلا کو پر کرنے کے لئے ہوا کرتی ہے جو ماضی سے
فرار کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے.ان ہلاکت خیز رجحانات کے علاوہ عالمی امن کے لئے بھی کٹر مذہبی عقائد کا
از سرنو احیاء ایک خطرہ بنا ہوا ہے.ایسے کڑر عقائد کے باعث فضا زہر آلود ہو جاتی ہے
جو نظریات کی اشاعت اور ان پر آزادانہ بحث کے لئے بہت مہلک ثابت ہوتی ہے.دوسرے یہ کہ بدعنوان سیاست دان ایسی دھما کہ خیز صورت حال سے ناجائز فائدہ
اٹھانے پر ہمیشہ کمر بستہ رہتے ہیں.مختلف مذاہب کے مابین صدیوں سے جاری
جھگڑے اور اختلاف بھی اس آگ کو مزید بھڑکاتے ہیں.مذہب کے نام پر ہونے
والے اس تمام فساد سے خود مذہب کا حسن داغدار ہوتا چلا جا رہا ہے.عالمی ذرائع
ابلاغ کا بھی اس میں ایک کردار ہے.عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ یہ ذرائع ابلاغ
آزاد ہیں لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے.دراصل ان کا کنٹرول پس پردہ کام کرنے
والے بعض ہاتھوں میں ہے اس لئے یہ کہنا درست نہیں ہے کہ دنیا کے معاملات میں
یہ ایک آزادانہ اور غیر جانبدارانہ کردار ادا کرتے ہیں.ایک ملک جہاں کی بھاری
اکثریت ایک مذہب کے ماننے والوں کی ہو وہاں کے ذرائع ابلاغ دوسرے مذہب
00
Page 21
کے خلاف جنگ میں شامل ہو جاتے ہیں اور اس طرح اقلیت کے مذہب کی تصویر کو
اور بھی زیادہ بگاڑ کر پیش کرتے ہیں اور صورت حال پیچیدہ سے پیچیدہ تر ہوتی چلی
جاتی ہے.اس تمام جھگڑے اور فساد میں بلاشبہ پہلا شکار خود مذہب ہوتا ہے.مذہب کی دنیا میں آج جو کچھ ہو رہا ہے میں فی الحقیقت اس کے بارہ میں بہت
پریشان اور فکر مند ہوں.آج اس امر کی فوری ضرورت ہے کہ مذاہب کے مابین
پائی جانے والی غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لئے ٹھوس اور سنجیدہ کوششیں کی جائیں.اور میں یقین رکھتا ہوں کہ اسلام ہی سب سے زیادہ احسن رنگ میں اور ہماری
ضرورتوں کے عین مطابق یہ کام سر انجام دینے کی صلاحیت رکھتا ہے.میں نے اس مضمون کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا ہے تاکہ بات زیادہ آسان
اور قابل فہم ہو جائے.مثلاً ایک ایسے مذہب کے لئے جو عالمی امن کے قیام میں ایک
مثبت کردار ادا کر سکتا ہے (اور جس میں عالمی سطح پر بنی نوع انسان کو متحد کرنے کی
صلاحیت بھی موجود ہے ) ضروری ہے کہ وہ پہلے خود مذہب کی آفاقیت پر یقین رکھتا
ہو.مذہب کی آفاقیت سے مراد یہ ہے کہ تمام بنی نوع انسان ایک خدا کی مخلوق ہیں
خواہ وہ کسی بھی رنگ ونسل سے تعلق رکھتے ہوں یا دنیا کے کسی بھی خطے میں آباد ہوں.چونکہ ان کا خدا ایک ہے اس لئے وہ سب اس بات میں برابر کے حقدار ہیں کہ انہیں
آسمانی ہدایت سے نوازا جائے.اگر خدا تعالیٰ نے کبھی کسی ایک قوم کی طرف وحی
نازل فرمائی ہے تو پھر ایک عالمگیر مذہب کو تسلیم کرنا چاہئے کہ جہاں تک حق کا سوال
ہے وحی الہی ہر قوم میں نازل ہو سکتی ہے.اب دیکھئے یہ نظریہ سچائی پر کسی ایک مذہب کی اجارہ داری کے تصور کو کس طرح
یکسر مٹا دیتا ہے.تمام مذاہب کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ یہ دعویٰ کریں کہ ہمارے پاس
کوئی آسمانی صداقت ہے.ان مذاہب کے نام اور عقائد خواہ کچھ بھی ہوں
Page 22
روئے زمین پر وہ جہاں کہیں بھی پائے جائیں یا تاریخ انسانی کے کسی بھی دور سے
تعلق رکھتے ہوں انہیں یہ حق حاصل ہے کہ وہ الہامی صداقتوں کے حامل ہونے کا
دعوی کریں.نیز یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ عقائد اور تعلیمات کے اختلاف کے
با وجود تمام مذاہب کا ماخذ ایک ہے.وہ قادر مطلق خدا جس نے کسی ایک خطہ زمین
میں ایک مذہب کو بھیجا لازم ہے کہ اس خدا نے دیگر علاقوں اور مختلف زمانوں کے
لوگوں کی مذہبی اور روحانی ضرورتوں کے پورا کرنے کا انتظام بھی کیا ہو.بعینہ یہی وہ
پیغام ہے جو قرآن کریم نے دنیا کو دیا ہے.انبیاء ہر قوم میں مبعوث ہوتے رہے ہیں
نبوت کی اس آفاقیت کے بارے میں قرآن مجید فرماتا ہے.٥٠
٠٥٠٠
ه و
ويت
هوو
وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلّ امَةِ رَسُولاً ان اعبدوا اللهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ :
( سورۃ النحل آیت ۳۷)
ترجمہ.اور یقیناً ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت
کرو اور بتوں سے اجتناب کرو.نیز قرآن کریم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے یہ اعلان بھی
کرتا ہے کہ صرف آپ ہی رسول نہیں چنانچہ فرمایا.وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُم مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنهم من لم نقصص
عَلَيْكَ
(سورۃ المومن آیت ۷۹ )
ترجمہ.اور یقیناً ہم نے تجھ سے پہلے بھی پیغمبر بھیجے تھے.بعض اُن میں
سے ایسے تھے جن کا ذکر ہم نے تجھ سے کر دیا ہے اور بعض اُن میں سے
10
Page 23
ایسے تھے جن کا ہم نے تجھ سے ذکر نہیں کیا.پھر قرآن مجید رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دلاتے ہوئے فرماتا ہے.28 0
إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌهِ إِنَّا اَرْسَلْنَكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَّ نَذِيرًا وَإِنْ مِنْ
280
أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيْهَا نَذِيرٌ
(سورة فاطر آیات ۲۴ تا ۲۵)
ترجمہ.تو تو محض ایک ڈرانے والا ہے.یقینا ہم نے تجھے حق کے ساتھ
بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے.اور کوئی امت نہیں مگر ضرور اس میں کوئی
ڈرانے والا گزرا ہے.قرآن مجید کی ان آیات سے خوب واضح ہو جاتا ہے کہ اسلام دیگر مذاہب کو
یکسر نظر انداز کر کے صداقت پر اپنی اجارہ داری کا ہرگز دعوی نہیں کرتا بلکہ واضح
اور معین طور پر یہ اعلان کرتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے دنیا کے سب خطوں اور سب زمانوں
میں اپنے رسول مبعوث فرمائے ہیں تاکہ بنی نوع انسان کی مذہبی اور روحانی
ضروریات پوری ہوسکیں.چنانچہ یہ رسول اپنی اپنی قوموں تک خدا تعالیٰ کا پیغام
پہنچاتے رہے ہیں.بلحاظ منصب تمام انبیاء برابر ہیں
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تمام بنی نوع انسان کی اصلاح کے لئے مختلف زمانوں
اور علاقوں میں جو انبیاء تشریف لاتے رہے ہیں کیا وہ اپنے منصب کے لحاظ سے
برابر ہیں؟ قرآن مجید کی رو سے تمام انبیا ء خدا تعالیٰ کی طرف سے ہی آتے رہے
ہیں.خدا تعالیٰ کے احکامات کو نافذ کرنے کا جو اختیار انہیں حاصل ہوتا ہے سب انبیاء
اسے پوری مضبوطی اور یقین کے ساتھ یکساں استعمال کرتے ہیں.کسی انسان کو یہ حق
11
Page 24
حاصل نہیں ہے کہ وہ انبیاء کے درمیان کسی قسم کا کوئی فرق روا ر کھے.سب انبیاء اور
ان کے لائے ہوئے پیغام کو مستند تسلیم کرنا لازم ہے.مذاہب عالم، بانیان مذاہب اور دیگر جملہ انبیاء کے متعلق اسلام کی یہ تعلیم مختلف
مذاہب کے درمیان مفاہمت اور اتحاد کی فضا قائم کرنے میں بہت اہم کردار ادا کر
سکتی ہے.یہ اصول کہ ہر نبی پر نازل ہونے والی وحی چونکہ ایک ہی خدا کی طرف سے
ہے اس لئے یکساں طور پر قابل احترام ہے مذاہب کو ایک دوسرے کے قریب لانے
کا بہت ہی موثر ذریعہ ثابت ہو سکتا ہے.اس سے دوسرے مذاہب کے انبیاء اور ان
کی وحی کے متعلق مخالفانہ جذبات ، ادب اور احترام کے جذبات میں بدل جاتے ہیں
اور قرآن کریم کا اس مسئلہ پر یہی واضح اور منطقی موقف ہے.چنانچہ فرمایا:
طو
امَنَ الرَّسُوْلُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهِ وَالْمُؤمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَئِكَتِهِ وَ
قف
كُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُّسُلِهِ وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا
غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ
(سورۃ البقرہ آیت ۲۸۶)
ق ز
ترجمہ.رسول اس پر ایمان لے آیا جو اس کے رب کی طرف سے اس کی
طرف اتارا گیا اور مومن بھی.ان میں سے ) ہر ایک ایمان لے آیا
اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر
یہ کہتے ہوئے کہ ) ہم اس کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان تفریق
نہیں کریں گے.اور انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت
کی.تیری بخشش کے طلب گار ہیں اے ہمارے رب! اور تیری طرف
ہی لوٹ کر جاتا ہے.پھر فرماتا ہے:
روو
إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ باللهِ وَرُسُلِهِ وَيُريدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرَسُلِهِ وَيَقُولُونَ
12
Page 25
نومن
ه وو
لا ل و ه وه - - لک لک
و نكفر ببعض ويريدون أن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَيْلاه
8 05
أُولَئِكَ هُمُ الْكَفِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَفِرِينَ عَذَابًا مُّهِيْنًا وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ
روو
هوه آ
ووه وه
وَكَانَ
وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولئِكَ سَوْفَ يُوتِيْهِمْ أَجُورَهُمْ.(سورۃ النساء آیات ۱۵۱ تا ۱۵۳)
= 0
غَفُورًا رَّحِيمًا
الله
ترجمہ.یقیناً وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں اور
چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں اور کہتے
ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لائیں گے اور بعض کا انکار کر دیں گے اور چاہتے
ہیں کہ اس کے بیچ کی کوئی راہ اختیار کریں.یہی لوگ ہیں جو پکے کافر
ہیں اور ہم نے کافروں کے لئے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا
ہے.اور وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور ان کے
اندر کسی کے درمیان تفریق نہ کی ، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں وہ ضرور ان
کے اجر عطا کرے گا.اور اللہ بہت بخشنے والا (اور ) بار بار رحم کرنے والا
ہے.کیا منصب میں برابری کے باوجود انبیاء کے مرتبہ اور مقام میں فرق
ہو سکتا ہے؟
اگر تمام انبیاء اپنے منصب کے لحاظ سے برابر ہیں تو کیا یہ ضروری ہے کہ وہ
مرتبہ کے لحاظ سے بھی برابر ہوں؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ انبیاء اپنے ذاتی
اوصاف اور فرائض کی ادائیگی کے طریق میں کئی اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف
ہو سکتے ہیں.قرب الہی کے لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں انبیاء اور رسل کے
مراتب میں فرق ہو سکتا ہے.اس امر کی تصدیق بائبل، قرآن اور دیگر صحائف میں
13
Page 26
مذکور تاریخ انبیاء کے مطالعہ سے بخوبی ہو جاتی ہے.قرآن مجید اس امر کو تسلیم کرتا ہے کہ منصب میں مساوی ہونے کے باوجود انبیاء
کے مراتب میں فرق ہو سکتا ہے.لیکن یہ ایسا فرق نہیں جس کی وجہ سے مختلف مذاہب
کے ماننے والے آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں.قرآن کریم جہاں یہ
اعلان کرتا ہے کہ سب انبیاء خدا کی طرف سے ایک جیسا مستند پیغام لے کر آئے ہیں
وہاں یہ اعلان بھی کرتا ہے کہ.و و
و
تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنهم من كلم الله و رفع بعضهم
(البقره آیت ۲۵۴)
درجت
ترجمہ.یہ وہ رسول ہیں جن میں سے بعض کو ہم نے بعض ( دوسروں ) پر
فضیلت دی.بعض ان میں سے وہ ہیں جن سے اللہ نے (روبرو) کلام
کیا اور ان میں سے بعض کو ( بعض دوسروں سے ) درجات میں بلند کیا.اس امر کو تسلیم کرنے کے بعد کہ منصب نبوت میں مساوی ہونے کے باوجود انبیاء
کے مرتبہ اور مقام میں فرق ہو سکتا ہے ایک سوال ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر
زیادہ بلند مرتبہ نبی کون ہے یا کس کو سمجھا جائے ؟ یہ ایک بہت نازک اور حساس مسئلہ
ہے.مگر اس کی اہمیت کو نظر انداز بھی نہیں کیا جا سکتا.ظاہر ہے کہ تمام مذاہب کے پیرو اپنے اپنے مذہب کے بانی کو سب انبیاء سے
افضل قرار دیتے ہیں.سب یہ
سمجھتے ہیں کہ مرتبہ شان تقدس اور عزت کے لحاظ سے
کوئی اور ان کے نبی کے ہم پلہ نہیں ہو سکتا اور نبوت کے تمام لازمی اوصاف میں سب
سے بلند اور ارفع و اعلیٰ مقام پر فائز ہمارا ہی نبی ہے.اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا
مسلمان بھی یہ دعوی کرتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ سب نبیوں سے افضل ہیں؟
اس کا جواب یہ ہے کہ بلاشبہ اسلام دوٹوک الفاظ میں یہ دعویٰ کرتا ہے اور یہ
صلى الله
14
Page 27
اعلان کرتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صفات حسنہ کے لحاظ سے
بلند ترین مقام پر فائز ہیں اور آپ ہی افضل الرسل ہیں.مگر یہ بات یاد رکھنی چاہئے
کہ اسلام کے اس دعوئی اور دوسرے مذاہب کے دعاوی میں ایک بڑا واضح اور
بنیادی فرق ہے.اول تو یہ بات پیش نظر رہنی چاہئے کہ صرف اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جو
نبوت کی آفاقیت کو تسلیم کرتا ہے.اسلام کے نزدیک دنیا کی ہر قوم اور خطہ میں انبیاء
مبعوث ہوتے رہے ہیں.لیکن مثال کے طور پر یہود عہد نامہ قدیم میں مذکور
انبیاء کرام کے علاوہ دوسرے انبیاء کو تسلیم ہی نہیں کرتے.چنانچہ جب وہ حضرت
موسیٰ علیہ السلام کے عظیم ترین نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ
السلام کا موازنہ حضرت بدھ علیہ السلام سے نہیں کر رہے ہوتے.وہ تو عظیم بانیان
مذاہب کے دعوئی ہی کو تسلیم نہیں کرتے.ان کے نزدیک مذکورہ بالا تمام انبیاء برحق
نہیں ہیں.یہاں تک کہ ان کے خیال کے مطابق یہ امر ناممکن ہے کہ ان کے مسلمہ
انبیاء کے علاوہ بھی کوئی نبی ہو.پس ایک طرف تو یہود کے اپنے مسلمہ انبیاء میں سے کسی ایک نبی کی فضیلت کا
عقیدہ ہے اور دوسری طرف اسلام کا دعویٰ کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
افضل ترین نبی ہیں، یہ دونوں دعاوی اپنی نوعیت کے لحاظ سے بالکل مختلف ہیں.اس
کی وجہ یہ ہے کہ یہودیت کی تعلیم کے مطابق بائبل میں مذکور انبیاء کے علاوہ دوسرا
کوئی نبی موجود ہی نہیں ہے.جبکہ اسلام سب قوموں میں سچے انبیاء کے مبعوث کئے
جانے کی تعلیم دیتا ہے.یہودیت کی طرح بدھ ازم، زرتشت ازم اور ہندو ازم وغیرہ
سب مذاہب کے ایسے دعاوی کی بالکل یہی صورت ہے.ایک فرق اور بھی ہے جسے ذہن میں رکھنا ضروری ہے.نبیوں اور رسولوں کا جو
15
Page 28
تصور یہودیت، عیسائیت اور اسلام میں پایا جاتا ہے دیگر اکثر مذاہب کے ہاں پایا
جانے والا تصور اس سے بالکل مختلف ہے.وہ اپنے مقدس مذہبی وجودوں کو ہمیشہ
صرف خدا کا فرستادہ ہی نہیں سمجھتے بلکہ ان کے نزدیک ان کے مذاہب کے بانی عام
انسانوں سے بالاتر اپنی ذات میں مقدس وجود ہیں.بعض کے نزدیک وہ خدا کے
اوتار ہیں.یہاں تک کہ بعض کو خدا ہی قرار دیا جاتا ہے.یا پھر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ
مقدس مذہبی لوگ رفتہ رفتہ خدائی کے مقام تک پہنچنے والے کوئی ممتاز وجود ہیں.عیسائیت نے حضرت عیسی علیہ السلام کے ساتھ بھی کچھ ایسے ہی تصورات وابستہ کر
رکھے ہیں.اس لئے وہ بھی اس ذیل میں آجاتے ہیں.مگر اسلام کی تعلیم کے مطابق
ایسے تمام خدا یا خدا کے بیٹے اور بچے اور خدا کے اوتار سب نام نہاد اور فرضی باتیں
ہیں.درحقیقت یہ لوگ صرف خدا تعالیٰ کے بھیجے ہوئے انبیاء ہیں جنہیں ان کے
ماننے والوں نے بہت بعد میں خدائی کے درجہ تک پہنچا دیا.مذاہب میں انبیاء کو
دیوتا بنانے کا یہ عمل بتدریج واقع ہوتا ہے.ایسے عقائد ایک نبی کے زمانہ میں اچانک
جنم نہیں لیا کرتے.بلکہ یہ تصورات رفتہ رفتہ تشکیل پاتے ہیں.اس موضوع پر تو ہم
آگے چل کر مزید تفصیل سے بات کریں گے.سردست یہ بتانا مقصود ہے کہ اسلام
جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جملہ انبیاء پر فضیلت کا اعلان کرتا ہے تو تمام
مذاہب کے مقدس وجود انبیاء کے زمرہ میں نبوت کے اس تصور کے مطابق شامل
ہوتے ہیں جو یہودیت اور اسلام کا ہے.یہاں یہ بات دہرانی مناسب ہوگی کہ تمام
الہامی مذاہب کے بانیوں کے متعلق اسلام کا عقیدہ کیا ہے؟ اسلام کے نزدیک وہ
سب انسان ہی تھے جنہیں خدا تعالیٰ نے نبوت کے منصب پر فائز کر کے دنیا میں
مبعوث فرمایا.مختلف زمانوں اور مختلف علاقوں میں جہاں کہیں بھی انبیاء آئے
بلا استثناء وہ سب انسان ہی تھے.جیسا کہ قرآن کریم بیان فرماتا ہے.16
Page 29
فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَّ جِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا
(النساء آیت ۴۲)
ترجمہ.پس کیا حال ہوگا جب ہم ہر ایک امت میں سے ایک گواہ لیکر
آئیں گے.اور ہم تجھے ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے.پس اسلامی نقطہ نگاہ سے یہ امر بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر
زمانہ اور ہر قوم میں رسول آئے اور وہ سب کے سب انسان تھے.آئیے اب ہم قرآن مجید کی رو سے رسول مقبول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کے مقام اور مرتبہ کا مطالعہ کرتے ہیں.چنانچہ بانی اسلام حضرت اقدس
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن کریم کا سب سے زیادہ قابل توجہ نمایاں
اور ناقابل تردید دعوئی درج ذیل آیت میں کیا گیا ہے.یہ ایک بہت معروف آیت
ہے جو اکثر زیر بحث آتی رہتی ہے.مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلكِنْ رَّسُوْلَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّنَ ، وَكَانَ
اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا
(سورۃ الاحزاب آیت ۴۱)
ترجمہ - محمدؐ تمہارے (جیسے ) مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں بلکہ وہ
اللہ کا رسول ہے اور سب نبیوں کا خاتم ہے.اور اللہ ہر چیز کا خوب علم
رکھنے والا ہے.اس آیت میں عربی لفظ خاتم بہت سے معانی رکھتا ہے تاہم خاتم النَّبِيِّنَ کے
لقب کے بنیادی معنی بلاشبہ بہترین ، سب سے افضل، سب سے بڑھ کر صاحب اختیار،
سب پر حاوی اور دوسروں کی تصدیق کرنے والا ہیں.(حوالہ کے لئے دیکھیں.لین، اقرب
الموارد، مفردات امام راغب، زرقانی)
حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت کا ذکر ایک اور آیت میں بھی کیا
17
Page 30
گیا ہے.اور یہ آیت اس اعلان پر مشتمل ہے کہ آپ کی تعلیمات ہر لحاظ سے مکمل
اور آخری ہیں.فرمایا:
وو
الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ
دينا.(سورۃ المائدہ آیت ۴)
ترجمہ.آج کے دن میں نے تمہارے لئے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر
میں نے اپنی نعمت تمام کر دی ہے اور میں نے اسلام کو تمہارے لئے دین
کے طور پر پسند کر لیا ہے.اس دعوی سے واضح طور پر یہ بات مستنبط ہوتی ہے کہ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں سے اکمل ترین تعلیم دینے والے ہیں اور آپ سب
نبیوں میں بلند ترین مقام پر فائز ہیں.اس مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بہ
یقین دلایا ہے کہ جو کتاب آپ پر نازل کی جارہی ہے اس کی حفاظت کی جائے گی.اس کے متن کو انسانی دست برد سے محفوظ رکھا جائے گا.اور یوں دراصل یہ دعویٰ کیا
گیا ہے کہ نہ صرف قرآنی تعلیم ہر لحاظ سے مکمل ہے بلکہ یہ اپنی اصل شکل میں ہمیشہ
قائم رہنے والی بھی ہے.جس سے مراد یہ ہے کہ جن الفاظ میں یہ تعلیم آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی ہے بعینہ انہی الفاظ میں یہ ہمیشہ قائم و دائم رہے گی اور
قسم کی تحریف کا شکار نہیں ہوگی.چنانچہ گزشتہ چودہ سو سال کی تاریخ اس دعوی کی
صداقت پر گواہ ہے.قرآن کریم کی حفاظت کے سلسلہ میں آیات میں سے
مندرجہ ذیل بھی ہیں.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :
إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ، لَحْفِظُوْنَ
( سورة الحجر، آیت ۱۰)
ترجمہ.یقینا ہم نے ہی یہ ذکر اتارا ہے اور یقینا ہم ہی اس کی حفاظت
18
Page 31
کرنے والے ہیں.و وہ
ه وه
بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظ (سورۃ البروج آیات ۲۲، ۲۳)
ترجمہ.بلکہ وہ تو ایک صاحب مجد قرآن ہے ایک لوح محفوظ میں.ان آیات کی رو سے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف سب
سے افضل قرار دیا گیا ہے بلکہ آخری اور دائمی شریعت لانے والا بھی قرار دیا گیا
ہے.نیز یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آپ کی نبوت قیامت تک جاری وساری رہے گی.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کے اس دعوی کے متعلق یہ سوال اٹھایا
جاسکتا ہے کہ ایسا دعوئی دیگر مذاہب کے ماننے والوں پر ناگوار تو نہیں گزرے گا.اور
کیا یہ مذاہب کی باہمی افہام و تفہیم کو نقصان پہنچانے والا دعویٰ تو نہیں ہے.پھر یہ کہ
اس دعوی کو آج کے خطاب کے موضوع سے کیسے ہم آہنگ کیا جائے گا ؟ کیوں کہ
مجھے آج یہاں یہی بیان کرنا ہے کہ اسلام حیات انسانی کے تمام شعبوں اور دائروں
میں امن کی ضمانت دیتا ہے.اور ظاہر ہے کہ مذہب کا دائرہ انسانی زندگی میں بڑی
اہمیت کا حامل ہے.پس کیا اس نوعیت کا دعویٰ امن اور بالخصوص مذہبی امن کا نقیض تو
نہیں قرار پائے گا.دراصل یہی وہ امکانی سوال تھا جس کے پیش نظر میں نے پہلے
اس دعوی کو قدرے تفصیل سے بیان کیا ہے.جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے تو ایک
غیر متعصب اور تحقیقی ذہن کو مطمئن کرنے کے لئے اس کا جواب ایک سے زائد طریق
سے دیا جاسکتا ہے.جیسا کہ پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے ایسے دعاوی بہت سے دوسرے مذاہب کے
پیروؤں کی طرف سے بھی کئے جاتے ہیں.ایک محقق کے لئے صحیح طریق یہی ہے کہ
وہ بلا وجہ جوش میں نہ آئے اور یہ دیکھے کہ کیا کوئی نبی واقعی دوسرے انبیاء کی نسبت یہ
دعویٰ کرنے کا حقدار ہے.جہاں تک دیگر مذاہب کے ماننے والوں کا تعلق ہے
19
Page 32
تو محض اس دعویٰ سے ان کے جذبات مجروح نہیں ہونے چاہئیں.خاص طور پر اس
لئے بھی کہ خود ان کی طرف سے بھی ایسے ہی دعاوی پیش کئے جاتے ہیں.جہاں تک اسلام کا تعلق ہے اس نے ایک قدم اور آگے بڑھ کر اس سلسلہ میں
بھی مسلمانوں کو شائستگی، انکسار اور دوسروں کے جذبات کے احترام کی تلقین کی ہے.اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کے متعلق
اپنے عقائد کا غیروں کے سامنے ایسے غیر محتاط انداز میں ذکر نہ کیا کریں جس سے ان
کی دل شکنی اور دل آزاری ہو.یہ مضمون آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی درج ذیل دو
احادیث کے ذریعہ روز روشن کی طرح کھل جاتا ہے.حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی اور حضرت یونس
علیہ السلام کے ایک پر جوش پیرو باہم بحث میں الجھ پڑے.دونوں نے اس تکرار کے
دوران اپنے اپنے نبی کو اعلیٰ اور افضل قرار دیا.ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس مسلمان
نے کچھ اس شدومد کے ساتھ یہ دعویٰ پیش کیا جس سے دوسرے شخص کے جذبات کو
ٹھیس پہنچی.وہ شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس صحابی
کے خلاف شکایت کی.اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب مسلمانوں کو مخاطب
کرتے ہوئے فرمایا.وهو
°
لا تُفَصِلُونِي عَلَى يونس بن متى (صحیح البخاری کتاب الانبیاء )
یعنی تم یونس بن متی کے بالمقابل میری فضیلت کا اظہار نہ کیا کرو.بعض شارحین اس حدیث سے الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں.انہیں یہ حدیث
قرآن مجید کے دعویٰ کے خلاف نظر آتی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت یونس ہی نہیں بلکہ تمام انبیاء سے افضل ہیں.لی اللہ علیہ وسم
دراصل ان کی توجہ اصل بات کی طرف نہیں گئی.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
20
20
Page 33
یہ
نہیں فرمایا کہ میں یونس نبی سے درجہ میں کم ہوں یا یہ کہ میں یونس نبی سے افضل نہیں
ہوں.آپ نے تو اپنے متبعین سے یہ فرمایا کہ وہ آپ کے افضل ہونے کا اظہار اس
رنگ میں نہ کریں جس سے دوسروں کے جذبات مجروح ہو سکتے ہوں.جو واقعہ پیش
آیا تھا اسے مدنظر رکھتے ہوئے اس ارشاد سے صرف ایک ہی نتیجہ نکالا جا سکتا ہے اور
وہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو ملائمت اور شائستگی اختیار کرنے کا
درس دے رہے ہیں.آپ یہ ہدایت فرما رہے ہیں کہ شیخی بگھارنے اور فخر کرنے
کے مرض میں کبھی مبتلا نہ ہوں.آپ کا منشا یہ تھا کہ آپ کے مقام ومرتبہ کے بارے
میں غیروں سے گفتگو میں احتیاط برتنی چاہئے مبادا ان کی دل شکنی ہو.غیر مہذب اور
ناشائستہ طریق سے بات کرنا تو اسلام کے اپنے مفاد کے خلاف ہے.اس طرح تو
اسلام کیلئے لوگوں کے دل و دماغ فتح کرنے کی بجائے نتیجہ اس کے برعکس نکلے گا.حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل کی ایک اور حدیث سے بھی
توثیق ہوتی ہے.اس حدیث میں بیان شدہ واقعہ کے مطابق ایک مسلمان ایک
یہودی کے ساتھ اسی نوعیت کی ایک بحث میں الجھ پڑا.دونوں نے اپنے اپنے روحانی
آقا کی فضیلت کے بارہ میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر دعوی کئے.اس دفعہ بھی
ایسا ہی ہوا کہ غیر مسلم نے یہی مناسب سمجھا کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
خدمت میں اس مسلمان کے طرز عمل کے خلاف شکایت کرے.حضرت رسول کریم
صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر وہی حلم اور انکسار دکھایا جو آپ کی عادت مبارکہ کا
حصہ تھا نیز آپ کو موقع کی نزاکت کا اچھی طرح احساس تھا.چنانچہ آپ نے اس
مسلمان کو سمجھایا اور شائستگی، ملائمت اور تہذیب کا درس دیتے ہوئے فرمایا.وها
لا تُفَصِلُونِي عَلى موسى
(صحیح البخاری کتاب الانبیاء )
ترجمہ.یعنی تم موسیٰ کے بالمقابل میری فضیلت کا اظہار نہ کیا کرو.21
224
Page 34
خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قرب کے لحاظ سے انبیاء کے نسبتی مراتب کا
فیصلہ کرنا اور پھر اس کا اعلان کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے.عین ممکن ہے کہ کسی ایک زمانہ اور مذہب کے نبی کے متعلق خدا کی خوشنودی کا
اظہار ایسے رنگ میں ہوا ہو جس سے یہ مترشح ہوتا ہو کہ وہ نبی ہی افضل ترین ہے.لیکن یہ سب جانتے ہیں کہ اعلیٰ ترین اور افضل ترین جیسے الفاظ ایک محدود زمان
و مکان کی نسبت سے بھی استعمال ہوئے ہیں.ان برگزیدہ وجودوں کے متعلق انتہائی
تعریف کے ایسے الفاظ استعمال ہوئے جن سے ان کے ماننے والوں میں ایک
لط فہمی پیدا ہو سکتی ہے کہ وہ اس وجود کو آنے والے سب زمانوں میں اور سب
برگزیدوں میں بہترین اور مقدس ترین یقین کرلیں، حالانکہ ان کی سب پر فضیلت ان
کے اپنے زمانہ تک محدود تھی.بہر حال کسی مذہب کے پیروؤں کا سچے دل کے ساتھ
اپنے پیشوا کو ایسے بلند مرتبہ کا حامل یقین کرنا دوسروں کی ناراضگی کا باعث نہیں ہونا
چاہئے.تہذیب اور شائستگی کا تقاضا یہ ہے کہ ایسے امور کو اس رنگ میں پیش نہ کیا
جائے جس سے مختلف مذاہب کے درمیان سخی پیدا ہو.حضرت رسول کریم صلی اللہ
علیہ وسلم نے ان دو مسلمانوں کو جو بات سمجھائی اس کی دراصل یہی اہمیت اور حکمت
ہے.اگر تمام مذاہب عاجزی و انکساری اور تہذیب و شائستگی کے اس اصول کو اچھی
طرح اپنا لیں تو مذہبی دنیا میں باہمی اختلافات کی فضا کو خوشگوار بنایا جا سکتا ہے.نجات پر کسی ایک مذہب کی اجارہ داری نہیں ہو سکتی
انسان کی حقیقی نجات کا بظاہر سیدھا سادا سا مسئلہ بھی مذہبی دنیا کے امن کے لئے
ایک خطرہ بن سکتا ہے.خصوصا جب یہ دعویٰ کیا جائے کہ جو شخص شیطان سے بچنے اور
نجات کے لئے ایک خاص مذہب کو اختیار نہیں کرے گا وہ ابدی جہنم کا وارث ہوگا تو
22
222
Page 35
اس کا نتیجہ سوائے بدامنی کے اور کیا ہو سکتا ہے.ایک مذہب کو نجات اور گناہ سے
رہائی کا ذریعہ قرار دینا اور بات ہے لیکن ساتھ ہی یہ فتویٰ صادر کر دینا کہ جو شخص
حصول نجات کے لئے اس مذہب میں داخل نہ ہوگا وہ ضرور جہنم میں ڈالا جائے گا یہ
ایک بالکل مختلف بات ہے.بالفاظ دیگر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دوسرے مذاہب
کے لوگ رضائے الہی کے حصول کے لئے کتنی ہی کوششیں کیوں نہ کریں اپنے خالق
اور اس کی مخلوق سے
کتنا ہی پیار کیوں نہ کریں اور کیسی ہی نیکی اور پارسائی کے ساتھ
زندگی کیوں نہ گزاریں وہ بہر حال جہنم رسید ہوں گے.ان کا قصور اگر ہے تو صرف
اتنا کہ وہ نجات کے لئے اس خاص مذہب میں داخل نہیں ہوئے.جب ایسے کٹر اور
تنگ نظری اور عدم رواداری پر مبنی نظریہ کا اشتعال انگیز پیرایہ میں اظہار کیا جائے
جیسا که متشدد مذہبی لوگ عام طور پر کیا کرتے ہیں تو اس سے سخت فتنہ و فساد کا دروازہ
کھل جاتا ہے.دنیا میں طرح طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں.تعلیم یافتہ مہذب
اور شائستہ مزاج لوگوں کے ساتھ ساتھ جاہل اور اجڈ لوگ بھی ہوتے ہیں.ایک
مہذب اور تعلیم یافتہ انسان کے خلاف کوئی ایسی بات کی جائے تو اس کا رد عمل تہذیب
اور شائستگی کے دائرہ کے اندر رہتا ہے لیکن مذہبی رجحانات رکھنے والے لوگوں کی
ایک بڑی تعداد اپنے مذہبی جذبات کے مجروح ہونے پر بڑا شدید ردعمل دکھایا کرتی
ہے بلکہ ایسے لوگ تعلیم یافتہ بھی ہوں تو ان کا رد عمل بڑا سخت ہوتا ہے.بدقسمتی سے
تقریباً تمام مذاہب کے علماء کا ان لوگوں کے خلاف ایسا ہی رد عمل ہوتا ہے جو ان کے
ہم خیال نہیں ہوتے.قرون وسطی کے اکثر مسلمان علماء نے بھی یہی طریق اختیار کیا
تھا.انہوں نے کہا کہ حصول نجات کا ذریعہ صرف اسلام ہے.ان کی مراد اس سے
یہ تھی کہ ظہور اسلام کے بعد آج تک جتنے لوگ پیدا ہوئے اور دائرہ اسلام سے باہر
رہتے ہوئے مر گئے وہ سب کے سب ہمیشہ ہمیش کے لئے نجات سے محروم رہیں
23
223
Page 36
گے.عیسائیت کا نظریہ بھی اس سے مختلف نہیں ہے.میرے علم میں کوئی مذہب ایسا
نہیں جو اس سے مختلف نظریہ پیش کرتا ہو.لیکن میں اپنے سامعین کرام کو یقین دلانا
چاہتا ہوں کہ اسلام کی طرف ایسے کڑر نظریہ کو منسوب کرنے کا ہرگز کوئی جواز موجود
نہیں.قرآن کریم اس ضمن میں یکسر مختلف نظریہ پیش کرتا ہے.قرآن کریم کی رو
سے نجات پر کسی ایک مذہب کی اجارہ داری نہیں.وہ لوگ جنہیں اپنے آباؤ اجداد
سے غلط نظریات ورثہ میں ملے ہیں مگر وہ عام طور پر سچائی اور خلوص کے ساتھ زندگی
بسر کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ نجات سے محروم نہیں کئے جا سکتے.اسی طرح وہ
لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ کی نئی شریعت کا علم ہی نہیں ہوا اور وہ جانتے ہی نہیں کہ ہدایت
کے ایک نئے دور کا آغاز ہو چکا ہے ان پر بھی نجات کا دروازہ بند نہیں ہوگا بشرطیکہ
ان کی لاعلمی اپنی کوتا ہی یا غلطی کے باعث نہ ہو.نجات سے متعلق اس نکتہ کی وضاحت قرآن کریم کی یہ آیت کرتی ہے:
لِكُلّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوْهُ فَلا يُنَا زِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَى
رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُّسْتَقِيمٍ
(سورۃ الحج آیت ۶۸)
ترجمہ.ہر ملت کے لئے ہم نے قربانی کا طریق مقرر کیا ہے جس کے
مطابق وہ قربانی کرتے ہیں.پس وہ اس بارہ میں تجھ سے ہر گز کوئی
جھگڑا نہ کریں اور تو اپنے رب کی طرف بلا.یقینا تو ہدایت کی سیدھی راہ
پر گامزن) ہے.پھر اس مضمون کے تعلق میں ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے.إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِيْنَ هَادُوا وَالصَّبِئُونَ وَالنَّصْرِى مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الاخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ (سورة المائدہ آیت ۷۰)
24
Page 37
ترجمہ.یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور صابی اور
نصرانی جو بھی اللہ پر ایمان لایا اور یوم آخر پر اور نیک عمل بجا لایا ان پر
کوئی خوف نہیں اور وہ کوئی غم نہیں کریں گے.اہل کتاب کی اصطلاح اگر چہ بالعموم یہود و نصاریٰ کے لئے استعمال ہوتی
ہے لیکن درحقیقت اس کا دائرہ بہت وسیع ہے.قرآن کریم کی آیت کہ ” کوئی قوم
ایسی نہیں گزری جس میں کوئی ہوشیار کرنے والا نہ آیا ہو اور اس مضمون کی دیگر
آیات جن کا پہلے ذکر کیا جا چکا ہے ان سب کی روشنی میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش
نہیں رہتی کہ عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید یعنی تورات اور انجیل ہی صرف الہامی
کتب نہیں تھیں بلکہ بنی نوع انسان کی بھلائی اور رہنمائی کے لئے یقینا بعض اور کتب
بھی نازل کی گئی تھیں.اس لحاظ سے وہ تمام مذاہب جو یہ دعوی کرتے ہیں کہ ان کی
بنیاد وحی الہی پر ہے ان کے ماننے والے بھی اہل کتاب میں شامل سمجھے جائیں گے.مزید برآں اہل عرب ”صابی کی اصطلاح ان تمام غیر عرب اور غیر سامی
(non-semitic) مذاہب کے پیروؤں کے لئے استعمال کرتے تھے جن کے
پاس ان کی اپنی الگ الگ الہامی کتابیں تھیں.پس وحی الہی پر مبنی تمام مذاہب کے
ماننے والوں کو یقین دلایا گیا ہے کہ اللہ انہیں کوئی سزا نہیں دے گا اور نہ ہی وہ نجات
سے محروم رکھے جائیں گے.لیکن شرط یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے
نئے مذاہب کو شناخت نہ کر سکنے کا ان کے پاس کوئی حقیقی اور جائز عذر ہو.نیز وہ
اپنے آباء و اجداد کے مذاہب کی اقدار پر سچائی اور دیانت داری کے ساتھ قائم
ہوں.قرآن مجید اپنے اپنے مذہب پر پورے خلوص سے عمل کرنے والی ہر جماعت
سے خواہ وہ یہود و نصاریٰ میں سے ہو یا صابی ہو یہ وعدہ کرتا ہے:.فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ
(سورۃ البقرہ آیت ۶۳ )
25
25
Page 38
ترجمہ.ان سب کے لئے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان پر
کوئی خوف نہیں اور نہ وہ غم کریں گے.وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَةَ وَالانْجِيلَ وَمَا أنْزلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَّبِّهِمْ لَا كَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ
ط
وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ
(سورۃ المائدہ آیت ۶۷)
ترجمہ.اور اگر وہ توراۃ اور انجیل ( کی تعلیم ) کو اور جو کچھ ان کی طرف
ان کے رب کی طرف سے اتارا گیا قائم کرتے تو وہ اپنے اوپر سے بھی
کھاتے اور اپنے پاؤں کے نیچے سے بھی.ان میں سے ہی ایک جماعت
میانہ رو ہے جبکہ ان میں سے بہت ہیں کہ بہت برا ہے جو وہ کرتے
ہیں.لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتب أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَتِ اللَّهِ آنَاءَ الَّيْلِ وَهُمْ
يَسْجُدُون يُؤْمِنُوْنَ باللهِ وَالْيَوْمِ الآخِر وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَيُسْرِعُوْنَ فِي الْخَيْرَتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّلِحِيْنَ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ
فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ (سورۃ آل عمران آیات ۱۱۴ تا ۱۱۶)
ترجمہ.وہ سب ایک جیسے نہیں.اہل کتاب میں سے ایک جماعت (اپنے
مسلک پر ) قائم ہے.وہ رات کے اوقات میں اللہ کی آیات کی تلاوت
کرتے ہیں اور وہ سجدے کر رہے ہوتے ہیں.وہ اللہ پر ایمان لاتے
ہیں اور یوم آخر پر اور اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں اور بری باتوں سے
روکتے ہیں اور نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش
کرتے ہیں اور یہی ہیں وہ جو صالحین میں سے ہیں.اور جو نیکی بھی وہ
کریں گے تو ہر گز ان سے اس کے بارہ میں ناشکری کا سلوک نہیں کیا
جائے گا.اور اللہ متقیوں کو خوب جانتا ہے.26
26
Page 39
یہ خیال غلط ہے کہ اسلام کے نزدیک تمام یہود جہنمی ہیں.یہ تصور اس دور میں
یہودیوں اور مسلمانوں کی باہمی سیاسی کشمکش کے نتیجہ میں پیدا ہوا ہے.قرآن کریم کی جو
آیات میں بیان کر چکا ہوں ان کی روشنی میں ایسا خیال بالکل غلط ثابت ہو جاتا ہے.میرے اس موقف کی مندرجہ ذیل آیت بھی تائید کرتی ہے.° °
وه آ
وه ده وه
ومن قومِ موسى امة يهدونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ (سورۃ الاعراف آیت ۱۶۰)
ترجمہ.اور موسیٰ کی قوم میں بھی کچھ ایسے لوگ تھے جو حق کے ساتھ
لوگوں کو ) ہدایت دیتے تھے اور اسی کے ذریعہ سے انصاف کرتے
تھے.مذاہب کے مابین ہم آہنگی اور باہمی احترام کا فروغ
قرآن کریم میں واضح طور پر یہ اعلان کیا گیا ہے کہ صرف مسلمان ہی صداقت
کے علمبر دار نہیں ہیں بلکہ صداقتوں کے حامل اور لوگ بھی ہیں.اور صرف مسلمان ہی
نہیں جو تقویٰ کے ساتھ دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کے درمیان انصاف
کرتے ہیں بلکہ ایسی صفات اور لوگوں میں بھی پائی جاتی ہیں.مذاہب کے باہمی
تعلقات کو بہتر بنانے کے لئے یہی طرز فکر ہے جو پوری دنیا کو لازما اختیار کرنا
چاہئے.دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کے ساتھ ایسی وسیع النظری فراخ دلی
اور ہمدردی کے ساتھ افہام و تفہیم کو فروغ دیئے بغیر مذہبی امن کا قیام ممکن نہیں
قرآن مجید جملہ مذاہب عالم کا عمومی ذکر کرتے ہوئے اعلان کرتا ہے.وممن خلقنا امة يهدونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ (سورۃ الاعراف آیت ۱۸۲)
ترجمہ.اور ان میں سے جنہیں ہم نے پیدا کیا ایسے لوگ بھی تھے جو حق
ہے.27
Page 40
کے ساتھ (لوگوں کو ) ہدایت دیتے تھے اور اسی کے ذریعہ سے انصاف
کرتے تھے.مذہب کے عالمگیر ہونے کا نظریہ
زمانہ قدیم سے حکماء اور فلسفی اس وقت کا خواب دیکھتے رہے ہیں جب تمام
بنی نوع انسان ایک ہی خاندان کی طرح ہو جائیں گے.نوع انسانی کے اتحاد کا یہ
تصور صرف سیاسی مفکرین تک ہی محدود نہیں بلکہ اقتصادی اور معاشرتی علوم کے
ماہرین بھی اس نہج پر سوچتے رہے ہیں.مذہبی دنیا میں بھی یہ نظریہ پورے جوش و
خروش کے ساتھ موجود رہا ہے.بعض مذاہب تو عالمی غلبہ اور تسلط کی تمنا لئے بڑی
شدت سے مصروف عمل ہیں اور اس کے لئے انہوں نے زبردست منصوبے بھی بنائے
ہیں.اسی طرح اسلام بھی ساری دنیا کو ایک جھنڈے تلے جمع کرنا چاہتا ہے.اگر چہ
اسلام اور دیگر مذاہب میں بظاہر ایک نظریاتی اشتراک تو ضرور دکھائی دیتا ہے لیکن
اسلام کا موقف اس ضمن میں دوسروں سے بنیادی طور پر مختلف ہے.یہاں یہ بحث
اٹھانے کا موقع نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو ایک جھنڈے تلے جمع کرنے
کا کام کس مذہب کے سپرد کیا ہے البتہ یہ جاننا ضروری ہے کہ ایک سے زائد مذاہب
کی طرف سے ایسے دعوئی کے مضمرات اور ممکنہ نتائج کیا ہو سکتے ہیں.اگر دو تین یا
چار مذاہب جن کا تاریخی پس منظر بہت طویل ہے بیک وقت خود کو ان معنوں میں
عالمگیر قرار دیں تو کیا یہ بات لوگوں کو ایک ذہنی الجھن اور بے یقینی میں مبتلا نہیں کر
دے گی؟ کیا مذاہب کی باہمی عداوت اور عالمگیر غلبہ حاصل کرنے کی
امن عالم کیلئے ایک سنگین خطرہ نہیں بن جائے گی ؟ مختلف مذاہب کی طرف سے ایسی
جد و جہد
28
Page 41
عالمی تحریکیں موجود ہیں جنہیں آسانی سے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا بلکہ ان کا سنجیدگی
سے نوٹس لینا ضروری ہو جاتا ہے.ایسی تحریکات اگر غیر ذمہ دار تنگ نظر اور تشدد
پسند قیادت کے ہاتھوں میں چلی جائیں تو لامحالہ امکانی خطرات حقیقت کا روپ دھار
لیتے ہیں اور کئی گنا بڑھ جاتے ہیں.یہ پراپیگنڈہ کہ اسلام اپنے نظریات کی اشاعت و ترویج کے لئے طاقت کے
استعمال کی حوصلہ افزائی کرتا ہے مخالفین اسلام تو کرتے ہی ہیں مگر بدقسمتی سے کٹر
ملاؤں نے بھی ایسے خیالات کو فروغ دیا ہے.ان ملاؤں کے مزاج قرون وسطی کی
تنگ نظری اور تشدد پسندی کے آئینہ دار ہیں.ظاہر ہے کہ اگر ایک مذہب دوسرے
مذہب کے خلاف جارحیت کا راستہ اختیار کرتا ہے تو دوسرے مذہب کو یہ حق حاصل ہو
جاتا ہے کہ وہ بھی اپنے دفاع میں ویسے ہی ہتھیار استعمال کرے.میں ہرگز اس
پراپیگنڈہ سے متفق نہیں ہوں کہ اسلام اپنے نظریات کی اشاعت کے لئے طاقت کے
استعمال کا حامی ہے بلکہ اس کی پر زور تردید کرتا ہوں.تاہم اس پر تفصیلی گفتگو سے
پہلے ہم کسی مذہب کے عالمگیر ہونے کے دعوی کو عقلی معیار پر پرکھنے کی کوشش کرتے
ہیں یعنی یہ دیکھتے ہیں کہ کیا کسی مذہب کا پیغام عالمی اور آفاقی ہوسکتا ہے؟ مراد یہ ہے
کہ کیا اسلام ،عیسائیت یا کسی بھی مذہب کا پیغام ہر رنگ ونسل اور قومیت کے لوگوں پر
یکساں اطلاق پا سکتا ہے؟ کیا اس قدر مختلف نسلی، قبائلی اور قومی روایات، معاشرتی
عادات و اطوار اور ثقافتی رسوم و رواج کے ہوتے ہوئے ایک ہی پیغام سب کے لئے
قابل عمل ہو سکتا ہے؟ پھر سوال یہ ہے کہ کیا مذہب زمانی حدود و قیود سے بالا ہو سکتا
ہے؟ مذاہب جس آفاقیت کے مدعی ہیں اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ نہ صرف جغرافیائی
اور قومی حدود بلکہ زمانی حدود بھی مٹ جائیں.پس کیا مذہب کی تعلیمات اس زمانہ
کے لوگوں کے لئے ویسے ہی موزوں اور قابل عمل ہوسکتی ہیں جیسے وہ ایک ہزار سال
29
29
Page 42
قبل یا اس سے بھی پہلے زمانہ کے لوگوں کے لئے تھیں؟ اور اگر کسی ایک مذہب کو
عالمگیر سطح پر قبول کر بھی لیا جائے تو کیا ایسا مذہب آنے والی نسلوں کی ضروریات کو
پورا کر بھی سکے گا یا نہیں.اب یہ ہر مذہب کے پیروکاروں کا کام ہے کہ وہ بتائیں کہ
ان کے مذہب کی تعلیمات کی رو سے ان مسائل کا جنکا ہم نے اوپر ذکر کیا ہے کیا حل
ہے؟ اسلام ان مسائل کا جو حل پیش کرتا ہے میں اسے بہت اختصار کے ساتھ بیان
کرنا چاہوں گا.اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے
قرآن مجید نے بار بار اس امر کو واضح کیا ہے کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جسکی
تعلیمات فطرت انسانی کے عین مطابق ہیں.اسلام نے اس امر پر زور دیا ہے کہ
جس مذہب کی جڑیں انسانی فطرت میں پیوست ہوں وہ زمان و مکان کی حدود سے
بالا ہوتا ہے.بات دراصل یہ ہے کہ انسانی فطرت بنیادی طور پر کبھی تبدیل نہیں
ہوتی.یہی وجہ ہے کہ جو مذہب فطرت کے مطابق ہوگا اس میں اصولاً یہ صلاحیت
موجود ہوگی کہ وہ آفاقی مذہب بن سکے بشرطیکہ وہ انسانی ترقی کی کسی عارضی منزل اور
وقتی حالت میں حد سے زیادہ الجھ کر خود ہی اپنے آپ کو محدود نہ کرلے.پس جو
مذہب ان اصولوں پر قائم ہے جو فطرت انسانی سے پھوٹتے ہیں اس میں منطقی طور پر
یہ استعداد موجود ہوگی کہ وہ ایک عالمگیر مذہب بن سکے.اسلام نے تو اس سے بھی
ایک قدم اور آگے بڑھ کر اپنی منفرد بصیرت اور بالغ نظری کی وجہ سے یہاں تک
تسلیم کیا ہے کہ تمام مذاہب ایک حد تک آفاقیت کا عنصر اپنے اندر ضرور رکھتے ہیں
یعنی خدا تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہر مذہب میں ایک بنیادی اور مرکزی تعلیم
30
30
Page 43
ایسی ضرور ہوتی ہے جو ابدی صداقتوں پر مشتمل اور فطرت انسانی کے عین مطابق ہوا
کرتی ہے.مذاہب کی تعلیمات کا یہ مرکزی اور بنیادی حصہ تبدیل نہیں ہوتا تا وقتیکہ
ان مذاہب کے پیروکار بعد کے کسی زمانے میں اسکو بگاڑ نہ دیں.قرآن مجید کی درج
ذیل آیات سے یہ نکتہ خوب واضح ہو جاتا ہے.وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلوةَ وَيُؤْتُوا
الزَّكَوةَ وَ ذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ D
(سوره البیه آیت ۶)
ترجمہ.اور وہ کوئی حکم نہیں دیئے گئے سوائے اس کے کہ وہ اللہ کی عبادت
کریں، دین کو اس کے لئے خالص کرتے ہوئے ہمیشہ اس کی طرف جھکے
ہوئے.اور نماز کو قائم کریں.اور زکوۃ دیں.اور یہی قائم رہنے والی
تعلیمات کا دین ہے.فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّين حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ
لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ
( سورة الروم آیت ۳۱)
ترجمہ.پس (اللہ کی طرف) ہمیشہ مائل رہتے ہوئے اپنی توجہ دین پر
مرکوز رکھ.یہ اللہ کی فطرت ہے جس پر اس نے انسانوں کو پیدا کیا اللہ کی
تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں.یہ قائم رکھنے والا اور قائم رہنے والا دین
ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے.ان آیات کی روشنی میں ایک سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر تمام مذاہب بنیادی
طور پر ایک ہی تعلیم پر مشتمل تھے تو پھر یکے بعد دیگرے ان مذاہب کو بھیجتے چلے جانے
میں کیا حکمت پوشیدہ تھی؟ مزید برآں یہ کہ اگر تمام مذاہب ایک جیسی نا قابل تغیر اور
آفاقی تعلیم کے حامل تھے تو پھر اسلام دیگر مذاہب کے بالمقابل زیادہ مکمل اور عالمگیر
31
4
Page 44
مذہب ہونے کا دعویدار کیوں ہے؟
(1) پہلے سوال کے جواب میں قرآن مجید بنی نوع انسان کی توجہ ایک
نا قابل تردید تاریخی حقیقت کی طرف مبذول کراتا ہے.وہ یہ ہے کہ قرآن مجید سے
پہلے نازل ہونے والی کتب اور صحائف اپنی اصل شکل میں محفوظ نہیں ہیں.ان کی
تعلیمات میں بتدریج تبدیلیاں کی جاتی رہی ہیں یا پھر نئی باتیں شامل کی جاتی رہی ہیں
اور یوں ان میں بگاڑ پیدا ہوتا رہا ہے یہاں تک کہ ان کتب وصحائف کے مستند ہونے
کے بارہ میں بلکہ ان کی قانونی اور شرعی حیثیت کے متعلق شکوک وشبہات پیدا ہو گئے
ہیں.اب اس امر کا بار ثبوت ان مذاہب کے متبعین پر ہے کہ ان کے مسلمہ صحائف
میں کوئی تحریف یا تغیر و تبدل نہیں ہوا.اس سلسلہ میں جہاں تک قرآن مجید کا تعلق
ہے اسے سب آسمانی کتب وصحائف میں ایک منفرد اور ممتاز حیثیت حاصل ہے.اسلام کے اشد ترین مخالفین بھی جو قرآن کریم کو کلام الہی ہی تسلیم نہیں کرتے اس
بات کا اعتراف کرنے پر مجبور ہیں کہ بلا شبہ قرآن ایک غیر مبدل و غیر محرف کتاب
ہے.ان کو یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ یہ وہی قرآن ہے جس کے متعلق حضرت محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوئی فرمایا تھا کہ یہ خدا کا کلام ہے.مثال کے طور پر اس ضمن
میں سرولیم میور اور پروفیسر نولد یک (Noldeke) کے بیان درج کئے جا رہے ہیں.There is othewise every security,internal and external,that
we possess the text which Mohamet himself
and used.gave
forth
(Life of Mohamet by sir william muir, London, 1878,P.xxvii)
دو
اس بارہ میں اندرونی اور بیرونی ہر قسم کی شہادت موجود ہے کہ آج بھی
ہمارے ہاتھوں میں قرآن کا وہی متن ہے جو محمد (صلی اللہ علیہ وسلم ) نے
دیا تھا اور جسے خود آپ استعمال فرماتے تھے.(لائف آف محمد مصنفہ سرولیم میور مطبوعہ لندن 1878 - صفحہ 27)
32
Page 45
We may, upon the strongest assumption, affirm that every
verse in the Quran is the genuine and unaltered
composition of Mohamet himself.(Life of Mohamet by sir william muir, London, 1878,P.xxviii)
” ہم یقینی طور پر یہ تصدیق کر سکتے ہیں کہ قرآن کریم کی ہر آیت بعینہ
وہی ہے جو محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے خود بیان کی تھی.ہر آیت اصل
ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی.لائف آف محمد مصنفه سر ولیم میور مطبوعہ لندن 1878 - صفحہ 28)
Slight clerical errors there may have been, but the Quran
of Uthman contains none but genuine elements, though
somtimes in very strange order.The efforts of European
scholers to prove the existence of later interpolations in
the Quran have failed.(Prof.Noldeke in Encyclopaedia Brittanica; 9th edition under Quran)
" کتابت کی کچھ معمولی سی غلطیاں تو ہو سکتی ہیں لیکن اس میں کوئی شک
نہیں کہ حضرت عثمان کے قرآن کریم کا نسخہ اول تا آخر اصل قرآن
ہے.اگر چہ آیت کی ترتیب بعض جگہ بڑی عجیب دکھائی دیتی ہے.یورپ کے علماء کی کوششیں ناکام ہو چکی ہیں کہ وہ یہ ثابت کر سکیں کہ
( نزول کے بعد ) قرآن میں کسی قسم کی کوئی تحریف ہوئی ہے.( پروفیسر نولڈ یک انسائیکلو پیڈیا بریٹین کا ایڈیشن نمبر ۹ زیر لفظ قرآن )
یہ ایک بالکل مختلف بحث ہے کہ الہامی یا آسمانی کہلانے والی کتب میں سے کونسی
کتاب اصل میں کس کی تصنیف ہے.اس بحث سے قطع نظر یہاں ہم یہ ذکر کرنا چاہتے
ہیں کہ قرآن کریم کے متعلق دیگر اہل کتاب یہ چیلنج کرتے ہیں کہ وہ الہامی کلام نہیں
ہے.مگر دیکھئے وہی قرآن تو رات اور انجیل کے متعلق گواہی دیتا ہے کہ یہ جزوی طور پر
خدا کا کلام ہے.صرف تو رات اور انجیل ہی نہیں بلکہ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ دنیا کے
33
Page 46
دوسرے خطوں میں دیگر مذاہب کی کتب بھی بلاشبہ اسی خدا کی ہیں.جہاں تک ان میں
دکھائی دینے والے تضادات کا تعلق ہے قرآن انہیں انسانی
دست برد کا نتیجہ قرار دیتا ہے.اب ظاہر ہے کہ قرآن کریم کا دیگر مذہبی کتب کے متعلق
یہ نظریہ کہیں زیادہ حقیقت پسندانہ اور مذاہب کے مابین امن کو فروغ دینے والا ہے.(۲) دوسرے سوال کے ضمن میں قرآن مجید ہماری توجہ انسانی معاشرہ کے ہر
شعبہ میں جاری ارتقائی عمل کی طرف مبذول کرواتا ہے.نئے مذہب کی ضرورت
اولاً اس لئے تھی کہ پرانے مذہب کی اس بنیادی تعلیم کو از سرنو زندہ کیا جائے جس میں
لوگوں نے بگاڑ پیدا کر دیا تھا.دوسری وجہ یہ تھی کہ معاشرہ کے ارتقاء کے ساتھ قدم
ملا کر چلا جا سکے.(۳) یہی نہیں بلکہ مذاہب میں تبدیلی کے اس عمل کا ایک اور بھی محرک تھا کہ
سابقہ مذاہب میں ثانوی حیثیت کی حامل بعض وقتی اور عارضی تعلیمات بھی دی گئی
تھیں جو محض ایک خاص دور کے اور خاص لوگوں کی ضروریات کو پوری کرتی تھیں.اس کے معنی یہ ہیں کہ مذاہب کی تعلیمات صرف غیر مبدل اصولوں کے ایک مرکزی
حصہ پر ہی مشتمل نہیں تھیں بلکہ ان میں ثانوی اور فروعی نوعیت کی حامل عبوری اور وقتی
تعلیمات بھی شامل تھیں.ظاہر ہے کہ وقت گزرنے کے بعد ان تعلیمات کا تبدیل
ہونا ناگزیر تھا.(۴) ایک اور بات جو اپنی اہمیت کے لحاظ سے کسی طرح کم نہیں ہے، یہ ہے کہ
انسان کی روحانی تعلیم و تربیت کا سفر در حقیقت ایک ہی جست میں طے نہیں ہوا بلکہ
بتدریج ہوا ہے.یہاں تک کہ انسان اتنی ذہنی بلوغت کو پہنچ گیا اور اس قابل ہو گیا
کہ ان تمام بنیادی اور دائمی اصولوں کا علم اسے عطا کر دیا جائے جو اس کی کامل
ہدایت کے لئے ضروری تھے.قرآن کریم کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ وہ ثانوی اور
34
Page 47
ذیلی تعلیم جو دائی اور بنیادی اصولوں پر مبنی تھی اپنی آخری مکمل اور افضل ترین شکل
میں ایک کامل مذہب یعنی اسلام کے ایک حصہ کے طور پر نازل کر دی گئی.پرانی
تعلیمات کا وہ حصہ جو علاقائی اور وقتی نوعیت کا تھا اسے حذف کر دیا گیا اور تعلیمات کا
وہ حصہ جس کی آئندہ بھی ضرورت تھی اسے برقرار رکھا گیا اور قرآن کریم کے ذریعہ
دنیا کو پھر سے عطا کر دیا گیا.مذہب کے عالمگیر ہونے کے متعلق اسلامی نظریہ کا لب
لباب یہی ہے اور انہیں معنوں میں اسلام ایک آفاقی مذہب ہے.اب یہ لوگوں کا
کام ہے کہ وہ تحقیق کریں اور اس امر کا تقابلی جائزہ لیں کہ کونسا مذہب در حقیقت
عالمگیر اور آفاقی ہے.اب ہم پھر ان مذاہب کے مسئلہ کی طرف آتے ہیں جنہوں نے عالمی غلبہ کے
حصول کو اپنا صح نظر بنایا ہوا ہے اور یہ بات صاف ظاہر ہے کہ اسلام بھی یہ منزل
حاصل کرنا چاہتا ہے.قرآن کریم کی پیشگوئی کے مطابق یہ مقدر ہے کہ اسلام ایک
دن بنی نوع انسان کا واحد مذہب بن کر ابھرے گا.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :
هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ
وَلَوْكَرِهَ الْمُشْرِكُونَ
(سورۃ الصف آیت ۱۰)
ترجمہ.وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ
بھیجا تا کہ وہ اسے دین (کے ہر شعبہ ) پر کلیۂ غالب کر دے خواہ مشرک
برا منائیں.اگر چہ اسلام مختلف مذاہب کے مابین صلح و آشتی کے فروغ پر غیر متزلزل یقین
رکھتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسلام مختلف مذاہب کے درمیان صحت مند مقابلہ کا
قائل بھی ہے.وہ اس بات کی حوصلہ شکنی نہیں کرتا کہ لوگ اپنے اپنے مذہب کے
35
55
Page 48
پیغام اور نظریات کو پھیلائیں اور دوسرے مذاہب پر اپنے مذہب کی فضیلت اور
برتری ثابت کرنے کی کوشش کریں.امر واقعہ یہ ہے کہ خود اسلام سب ادیان پر اپنے آخری غلبے کو ایک عظیم الشان
اور ارفع منزل قرار دیتا ہے اور مسلمانوں کو ہمیشہ اس منزل کے حصول کیلئے کوشاں
رہنے کی تلقین اور تاکید کرتا ہے.قرآن کریم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب
کرتے ہوئے فرماتا ہے.قُلْ يَا يُّهَا النَّاسُ إِنِّى رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا نِ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَواتِ
وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِ وَيُمِيتُ قَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ
الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ كَلِمَتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (سورۃ الاعراف آیت ۱۵۹)
ترجمہ.تو کہہ دے کہ اے انسانو! یقیناً میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول
ہوں جس کے قبضے میں آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے.اس کے سوا
اور کوئی معبود نہیں.وہ زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے.پس ایمان
لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول نبی امی پر جو اللہ پر اور اس کے کلمات
پر ایمان رکھتا ہے اور اسی کی پیروی کرو تا کہ تم ہدایت پا جاؤ.تاہم اسلام ایک واضح ضابطہ اخلاق بھی دیتا ہے تا کہ مختلف مذاہب کے ماننے
والوں کے درمیان
کسی قسم کی کشیدگی پیدا نہ ہو اور رنجشیں اور غلط فہمیاں جنم نہ لیں.یہ
ضابطہ اخلاق حسن معاملہ، انصاف اور آزادی تقریر و تحریر کو یقینی بناتا ہے اور دوسروں
سے اختلاف رکھنے کا سب کو یکساں حق دیتا ہے.اشاعت دین کے ذرائع : جبر کی بکلی نفی
یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی مذہب عالمگیر ہونے کا دعوی بھی کرے اور مختلف مذاہب
36
36
Page 49
کے درمیان کشیدگی پیدا کرنے کا باعث بھی بنے.یا ایک عالمگیر پیغام کا حامل کوئی بھی
مذہب جو تمام بنی نوع انسان کو ایک جھنڈے تلے جمع کرنا چاہتا ہو، اپنے پیغام کی
اشاعت کے لئے طاقت کا استعمال کرے.تلوار سے عارضی فتوحات تو ہوسکتی ہیں مگر
دل فتح نہیں کئے جا سکتے.طاقت سے سر تو جھکائے جا سکتے ہیں مگر دلوں پر حکومت نہیں
کی جاسکتی.اسلام اپنے پیغام کی اشاعت کی خاطر کسی قسم کے جبر کی ہرگز اجازت نہیں دیتا.چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ :
ج
لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ (سورة البقره آیت ۲۵۷) ق
ترجمہ.دین میں کوئی جبر نہیں.یقینا ہدایت گمراہی سے کھل کر نمایاں
ہو چکی.پس جب ہدایت اور گمراہی کا فرق خوب واضح ہو چکا تو دین میں جبر کی کوئی
ضرورت ہی باقی نہیں رہی.ہر انسان کو اختیار دینا چاہئے کہ وہ دیکھے اور خود فیصلہ
کرے کہ سچائی اور ہدایت کہاں ہے.خدا تعالیٰ رسول مقبول حضرت محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے متنبہ فرماتا ہے کہ اصلاح معاشرہ کی کوشش کرتے
وقت طاقت کے استعمال کا خیال بھی دل میں نہ آنے دیں.اسی طرح مندرجہ ذیل
آیت میں بحیثیت ایک مصلح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب اور مقام کو پوری
وضاحت سے بیان کر دیا گیا ہے.فَذَ َكرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكَرَه لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَّيْطِر 0
( سورۃ الغاشیہ آیات ۲۲.۲۳)
ترجمہ.پس بکثرت نصیحت کر.تو محض ایک بار بار نصیحت کرنے والا
ہے.تو ان پر داروغہ نہیں.37
Page 50
اس مضمون کے سلسلے میں مزید وضاحت فرماتے ہوئے حضرت رسول کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر یاد دلایا جا رہا ہے.فرمایا:
فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلْغُ
(سورۃ الشوریٰ آیت ۴۹)
ترجمہ.پس اگر وہ منہ پھیر لیں تو ہم نے تجھے ان پر پاسبان بنا کر نہیں
بھیجا.تجھ پر پیغام پہنچانے کے سوا اور کچھ فرض نہیں.ایسے نظریات کی تبلیغ سے اگر کوئی تنازعہ اٹھ کھڑا ہو اور فریق مخالف تشدد پر اتر
آئے تو ایسی صورت میں اسلام کا تاکیدی حکم ہے کہ مسلمان تحمل اور برداشت سے کام
لیں.صبر و استقامت کا نمونہ دکھا ئیں اور جہاں تک ممکن ہو تصادم اور لڑائی جھگڑے
سے بچنے کی پوری کوشش کریں.یہی وجہ ہے کہ جہاں مسلمانوں کو دنیا بھر میں اسلام
کا پیغام پہنچانے کی ہدایت کی گئی ہے وہاں ساتھ ہی ان کو ایک واضح اور معین ضابطہ
اخلاق بھی عطا کیا گیا ہے.اس موضوع سے متعلق قرآن کریم میں بہت سی آیات
ہیں جن میں سے چند ایک اس مضمون کی وضاحت کے لئے پیش کی جارہی ہیں.ط
أدْعُ إِلى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِين
( سورۃ النحل آیت ۱۲۶)
ترجمہ.اپنے رب کے راستہ کی طرف حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت
کے ساتھ دعوت دے اور ان سے ایسی دلیل کے ساتھ بحث کر جو بہترین
ہو.یقینا تیرا رب ہی اسے جو اس کے راستے سے بھٹک چکا ہو سب سے
زیادہ جانتا ہے اور وہ ہدایت پانے والوں کا بھی سب سے زیادہ علم رکھتا
ہے.38
Page 51
ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ
(سورۃ المومنون آیت ۹۷)
ترجمہ.اُس (طریق) سے جو بہترین ہے بدی کو ہٹا دے.ہم اسے
سب سے زیادہ جانتے ہیں جو وہ باتیں بناتے ہیں.اس آیت میں احسن کا جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کے معنی ہیں بہترین، انتہائی دلکش،
حسین و جمیل اور خوبصورت.دوسروں تک اسلام کا پیغام پہنچاتے وقت مومنوں پر جس
ضابطہ اخلاق کی پابندی ضروری ہے اس کی وضاحت کرتے ہوئے قرآن کریم فرماتا ہے:
وَالْعَصْرِه إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْره إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ وَ
تَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِه ( سورة العصر آیات ۲ تا ۴)
ترجمہ.زمانے کی قسم ! یقیناً انسان ایک بڑے گھاٹے میں ہے.سوائے ان
لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال بجالائے اور حق پر قائم رہتے ہوئے ایک
دوسرے کو حق کی نصیحت کی اور صبر پر قائم رہتے ہوئے ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت
کی.اس سلسلہ میں قرآن مجید مزید فرماتا ہے:
° -
ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَ تَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ
( سورة البلد آیت ۱۸)
ترجمہ.پھر وہ اُن میں سے ہو جائے جو ایمان لے آئے اور صبر پر قائم
رہتے ہوئے ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرتے ہیں اور رحم پر قائم رہتے
ہوئے ایک دوسرے کو رحم کی نصیحت کرتے ہیں.کون سا مذ ہب باقی رہے گا؟ ( بقائے اصلح)
قرآن مجید کی رو سے کسی مذہب کی بقاء اور انجام کار فتح کا تمام تر دارو مدار کسی
39
Page 52
مادی طاقت پر نہیں بلکہ ان سچے دلائل و براہین کی قوت پر ہوتا ہے جس پر وہ مذہب
قائم ہو.قرآن کریم کا موقف اس سلسلہ میں دوٹوک اور معین ہے.قرآن کریم
فرماتا ہے کہ حق کو مٹانے کے لئے اور باطل کی تائید میں خواہ کیسی ہی زبردست
طاقتیں بروئے کار لائی جائیں وہ ہمیشہ ناکام اور نامراد ر ہیں گی.دلائل اور براہین
کی قوت مادی ہتھیاروں کی طاقت پر بہر حال غالب آ کر رہتی ہے.چنانچہ
قرآن کریم فرماتا ہے.وده
وه لاو
هسه
قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلْقُوا اللَّهِ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةٌ كَثِيرَةً بِاذْنِ
اللهِ وَاللهُ مَعَ الصَّابِرِينَ
(سورۃ البقره آیت ۲۵۰)
ترجمہ.(تب) ان لوگوں نے جو یقین رکھتے تھے کہ وہ اللہ سے ملنے
والے ہیں کہا کہ کتنی ہی کم تعداد جماعتیں ہیں جو اللہ کے حکم سے
کثیر التعداد جماعتوں پر غالب آ گئیں.اور اللہ صبر کرنے والوں کے
ساتھ ہوتا ہے.اسلام کی برتری اور غلبے کے نظریے کو مذکورہ بالا ارشاد خداوندی کے سیاق وسباق
میں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہئے.قرآن کریم کی ایک اور آیت میں فرمایا.وه - ط
b
رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ أُولئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلا إِنَّ حِزْبَ اللهِ
الْمُفْلِحُونَ
(سورۃ المجادلہ آیت ۲۳)
هم
ترجمہ.اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے.یہی اللہ کا
گروہ ہیں.خبردار! اللہ ہی کا گروہ ہے جو کامیاب ہونے والے لوگ ہیں.تاریخ اسلام میں ہونے والی پہلی جنگ ” جنگ بدر“ کہلاتی ہے.اس جنگ میں
مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی جماعت کے بالمقابل مشرکین مکہ کی ایک بہت کثیر تعداد
صف آراء تھی جو سامان حرب سے پوری طرح لیس تھی.مسلمان اول تو تعداد میں
40
40
Page 53
بہت تھوڑے تھے دوسرے ان کے پاس ہتھیار بھی بہت کم اور معمولی قسم کے تھے جو نہ
ہونے کے برابر تھے.اس صورت حال میں مسلمانوں پر ایک دفاعی جنگ مسلط کر دی
گئی تھی.مسلمان اپنی ذاتی بقاء کے لئے نہیں بلکہ اپنے نظریے کے تحفظ کی خاطر جنگ
لڑنے پر مجبور تھے.چنانچہ قرآن کریم اس ضمن میں فرماتا ہے.لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَبَحْيُ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيْنَةِ ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ
(سورۃ الانفال آیت ۴۳)
ترجمہ.تا کہ کھلی کھلی حجت کی رو سے جس کی ہلاکت کا جواز ہو وہی ہلاک
ہوا اور کھلی کھلی حجت کی رو سے جسے زندہ رہنا چاہئے وہی زندہ رہے.اور
یقینا اللہ بہت سننے والا (اور ) دائمی علم رکھنے والا ہے.یہ دراصل وہ دائمی اصول ہے جس نے نوع انسانی کے ارتقاء میں اہم ترین
کردار ادا کیا ہے.بقائے اصلح (survival of the fittest) اس کا خلاصہ اور
لب لباب ہے یعنی جو زیادہ موزوں اور بہتر ہے وہی باقی رکھا جاتا ہے اور دراصل
زندگی کے ارتقاء کا طریق بھی یہی ہے.آزادی تقریر
کسی پیغام کو دنیا میں پھیلانے کے لئے بلکہ خود انسان کی عزت اور وقار کو بحال
کرنے کے لئے اظہار اور ابلاغ کی آزادی بے حد ضروری ہے.جب تک کوئی
مذہب شرف انسانیت کو قائم نہیں کرتا اور اس کی حفاظت نہیں کرتا وہ اس قابل نہیں کہ
اسے مذہب کا نام دیا جا سکے.قبل ازیں جو کچھ بیان ہو چکا ہے اس سے یہ واضح
ہو جانا چاہئے کہ اسلام جیسے مذہب کے لئے یہ ناممکن ہے کہ وہ اظہار رائے اور
41
Page 54
آزادی تقریر کا مخالف ہو.اس کے برعکس اسلام آزادی اظہار کے اصول کی جس
دلیری اور جرات کے ساتھ حمایت کرتا ہے اس کی مثال کسی اور نظریاتی نظام یا مذہب
میں دور دور تک نظر نہیں آتی.مثلاً قرآن کریم اعلان کرتا ہے.وہ
وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصْرَى تِلْكَ آمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُو
ا برهانكم إن كنتم صدقينO
ا
(سورۃ البقرہ آیت ۱۱۲)
ترجمہ.اور وہ کہتے ہیں کہ ہر گز جنت میں داخل نہیں ہوگا سوائے ان کے
جو یہودی یا عیسائی ہوں.یہ محض ان کی خواہشات ہیں.تو کہہ کہ اپنی
کوئی مضبوط دلیل تو لا ؤ اگر تم سچے ہو.پھر ایک جگہ فرمایا :
امِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هَذَا ذِكْرُ مَنْ مَّعِيَ وَذِكْرُ مَنْ
ووه
لاه وه ده و ه -
قَبْلِي بَلْ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُم مَعْرِضُونَ (سورۃ الانبیاء آیت ۲۵)
ترجمہ.کیا انہوں نے اس کے سوا کوئی معبود بنا رکھے ہیں.تو کہہ دے
کہ اپنی قطعی دلیل لاؤ.یہ ذکر ان کا ہے جو میرے ساتھ ہیں اور ان کا
ذکر ہے جو مجھ سے پہلے تھے.لیکن ان میں سے اکثر لوگ حق کا علم نہیں
رکھتے اور وہ اعراض کرنے والے ہیں.قرآن مجید میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:
( سورة القصص آیت ۷۶ )
وَنَزَعْنَا مِنْ كُلَّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ
عَنهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ
ترجمہ.اور ہم ہر امت سے ایک گواہ نکال لائیں گے اور کہیں گے کہ
اپنی برہان لاؤ.پس وہ جان لیں گے کہ حق اللہ کے اختیار میں ہے اور
جو کچھ وہ افتراء کیا کرتے تھے ان سے جاتا رہے گا.42
Page 55
نیز فرمایا:
أمْ لَكُمْ سُلْطَنٌ مُّبِينٌ، فَأْتُوا بِكِتِبِكُمْ إِنْ كُنتُمْ صَدِقِينَ
( سورة الصافات آیات ۱۵۸٬۱۵۷)
ترجمہ.یا تمہارے پاس کوئی غالب (اور ) روشن دلیل ہے؟ پس اپنی
کتاب لا ؤ اگر تم سچے ہو.آزادی کی حدود
آج ساری دنیا آزادی کے نعروں سے گونج رہی ہے.ان نعروں کی شدت
کہیں کم ہے اور کہیں زیادہ.دنیا کے مختلف حصوں میں ان نعروں کا مفہوم بھی مختلف لیا
جاتا ہے لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ آزادی کی قدر و قیمت اور اہمیت کے متعلق انسان
کا علم اور شعور بڑھ رہا ہے اور ہر جگہ حریت اور آزادی کی ضرورت شدت سے محسوس
کی جا رہی ہے.لیکن سوال یہ ہے کہ انسان کس چیز سے آزادی کا متمنی ہے؟ کیا وہ
غیر ملکی تسلط سے رہائی چاہتا ہے؟ کیا وہ آمریت، فسطائیت، مذہبی ملائیت یا
یک جماعتی آمرانہ نظام سے آزادی کا طالب ہے؟ کیا وہ ظالم اور ستم ڈھانے والی
جمہوریتوں کے ہاتھوں تنگ ہے یا بدعنوان نوکر شاہی کا ستایا ہوا ہے؟ کیا آج کا
انسان اس لئے پریشان حال ہے کہ غریب ممالک امیر ممالک کے اقتصادی چنگل
میں بری طرح پھنسے ہوئے ہیں؟ کیا وہ جہالت اور تو ہم پرستی سے نجات چاہتا ہے؟
کیا وہ جنسی لذات کی پرستش سے تنگ آچکا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ آج انسانیت کو ان
سب مصائب سے آزادی کی ضرورت ہے.اسلام ان تمام دکھوں اور مصیبتوں سے انسان کو رہائی دلانے کا علمبر دار ہے لیکن
43
Page 56
اس مقصد کے لئے وہ کوئی ایسا راستہ اختیار کرنے کے حق میں نہیں جس سے افراتفری
اور فتنہ و فساد پیدا ہو.اسلام اس امر کی حمایت نہیں کرتا کہ ان تمام معاشرتی عوارض
کو دور کرنے کے لئے ایک ایسے اندھے انتقام کا دروازہ کھول دیا جائے جس سے
بے گناہ اور معصوم لوگ بھی مارے جائیں.اس سلسلہ میں اسلام کا پیغام یہ ہے کہ
(سورۃ البقرہ آیت ۲۰۶)
وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ
ترجمہ.اور اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا.اسلام ہر دوسرے مذہب کی طرح متوازن آزادی پر زور دیتا ہے.اسلام کے
نزدیک آزادی کی عمارت ” کچھ لو کچھ دو“ کی بنیاد پر استوار ہونی چاہئے.یعنی فرد
معاشرہ کے لئے کچھ ذمہ داریاں اٹھائے اور معاشرہ فرد کو کچھ حقوق عطا کرے.معاشرہ کے حوالے سے مطلق آزادی کا نعرہ بالکل کھوکھلا بے معنی، غیر فطری اور
غیر حقیقی نعرہ ہے.بعض اوقات آزادی کے ایسے غلط معنی لئے جاتے ہیں اور اس کے
تصور کو اتنا غلط استعمال کیا جاتا ہے کہ آزادی تقریر کا حسین اصول بے حد بدنما
اور بدصورت بن کر رہ جاتا ہے.گالی گلوچ ، دوسروں کی عزت و آبرو پر حملے اور پاک
اور مقدس وجودوں کی تو ہین آخر کہاں کی آزادی ہے؟
مذہبی تقدس کی پامالی
جہاں تک اظہار و بیان کی آزادی کا تعلق ہے اسلام نے دوسرے مذاہب کے
مقابلہ میں ایک قدم اور آگے بڑھایا ہے.مذہبی تقدس کی تو ہین بلاشبہ اخلاقی اعتبار
سے قابل مذمت ہے مگر اسلام نے اس کی کوئی ظاہری سزا مقر ر نہیں کی.اس دور میں
اگر چه عام طور پر تو یہی خیال کیا جاتا ہے کہ مذہبی توہین کی اسلام نے سزا مقرر کی ہے
44
Page 57
لیکن میں نے قرآن کریم کا بار بار گہری توجہ کے ساتھ وسیع مطالعہ کیا ہے مجھے ایک
آیت بھی ایسی نہیں ملی جس میں مذہبی اہانت کو ایسا جرم قرار دیا گیا ہو جس کی سزا دینا
کسی انسان کے اختیار میں ہو.اگر چہ قرآن کریم کسی بھی قسم کی ناشائستہ حرکت اور
ایسے بیہودہ قول و فعل کی اجازت نہیں دیتا جس سے دوسروں کے نازک جذبات
مجروح ہوتے ہوں.لیکن بایں ہمہ قرآن کریم نہ تو گستاخی اور اہانت کی اس دنیا میں
کوئی سزا تجویز کرتا ہے اور نہ ہی اس بارہ میں کسی انسان کو سزا دینے کا کوئی اختیار
دیتا ہے.مذہبی تقدس کی پامالی کا قرآن کریم میں پانچ جگہ ذکر آیا ہے.عمومی رنگ میں یہ
مضمون اس آیت میں یوں بیان ہوا ہے.وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَبِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيَسْتَهْرَا بِهَا
ہووہ.(سورۃ النساء آیت ۱۴۱)
فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثِ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذَا مِّثْلُهُمْ إِنَّ اللهَ
جَامِعَ الْمُنفِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا
ترجمہ.اور یقیناً اس نے تم پر کتاب میں یہ حکم اتارا ہے کہ جب تم سنو کہ
اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے یا ان سے تمسخر کیا جا رہا ہے تو ان
لوگوں کے پاس نہ بیٹھو یہاں تک کہ وہ اس کے سوا کسی اور بات میں
مصروف ہو جائیں.ضرور ہے کہ اس صورت میں تم معا ان جیسے ہی ہو
جاؤ.یقینا اللہ سب منافقوں اور کافروں کو جہنم میں اکٹھا کرنے والا
ہے.وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِيْنَ يَخُوضُونَ فِى ابْتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيْثِ
ط - وه
غَيْرِهِ وَإِمَّا يَنسِينَّكَ الشَّيْطَنُ فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّلِمِينَ
(سورۃ الانعام آیت ۶۹)
45
Page 58
ترجمہ.اور جب تو دیکھے ان لوگوں کو جو ہماری آیات سے تمسخر کرتے
ہیں تو پھر ان سے الگ ہو جا یہاں تک کہ وہ کسی دوسری بات میں مشغول
ہو جائیں.اور اگر کبھی شیطان تجھ سے اس معاملہ میں بھول چوک
کروا دے تو یہ یاد آجانے پر ظالم قوم کے ساتھ نہ بیٹھ.مذہبی تقدس کی اہانت کس قدر مکروہ اور بھیانک فعل ہے مگر اس کے خلاف کیسا
حسین رد عمل پیش کیا گیا ہے.ایک تو اسلام کسی شخص کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ وہ
مذہب کی توہین کرنے والے کو سزا دینے کا کام اپنے ہاتھوں میں لے لے.دوسرے
وہ یہ بھی اعلان کرتا ہے کہ ایسی حرکت کے خلاف احتجاج کے طور پر ان لوگوں کی مجلس
سے اٹھ کر باہر آجانا چاہئے جہاں مذہبی اقدار کا مذاق اڑایا جا رہا ہو اور تمسخر اور
استہزاء سے کام لیا جا رہا ہو.ایسے لوگوں کے خلاف کوئی سخت قدم اٹھانا تو درکنار
قرآن کریم نے ان سے مستقل طور پر قطع کلامی کا حکم بھی نہیں دیا.قرآن کریم نے
خوب کھول کر بتا دیا ہے کہ ایسے لوگوں سے علیحدگی صرف اس عرصہ کے دوران ہوگی
جس میں وہ اہانت کے مرتکب ہو رہے ہوں.پھر سورۃ الانعام کی ایک اور آیت میں بھی اہانت کا ذکر ہے جس میں صرف
خدا تعالی کی شان ہی میں گستاخی کا ذکر نہیں کیا گیا بلکہ بتوں اور دیگر فرضی معبودوں کی
تو ہین کا سوال بھی امکانی طور پر زیر بحث لایا گیا ہے.اس آیت کی تلاوت کرتے
وقت انسان قرآنی تعلیم کے حسن کو دیکھ کر مسحور ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا.وده
وده
وَلَا تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ
زيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ، ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
ص
(سورۃ الانعام آیت (۱۰۹)
ترجمہ.اور تم ان کو گالیاں نہ دو جن کو وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں ورنہ وہ
46
Page 59
دشمنی کرتے ہوئے بغیر علم کے اللہ کو گالیاں دیں گے.اس طرح ہم نے
ہر قوم کو ان کے کام خوبصورت بنا کر دکھائے ہیں.پھر ان کے رب کی
طرف ان کو لوٹ کر جانا ہے.تب وہ انہیں اس سے آگاہ کرے گا جو وہ
کیا کرتے تھے.یہ بات بطور خاص توجہ کے لائق ہے کہ اس آیت میں براہ راست مخاطب
مسلمان ہیں.مسلمانوں کو مشرکوں کے بتوں اور دیگر فرضی خداؤں کی توہین کرنے
سے سختی سے منع کیا گیا ہے اور یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو
مخالف لوگ ردعمل کے طور پر اللہ تعالیٰ کی اہانت کے مرتکب ہو سکتے ہیں.اللہ تعالیٰ
کی تو ہین اور بتوں کی توہین کی اس امکانی بحث میں دونوں صورتوں میں کوئی جسمانی
سزا تجویز نہیں کی گئی ہے.اس تعلیم میں جو عملی سبق دیا گیا ہے وہ بڑی گہری حکمت
اپنے اندر رکھتا ہے.اگر کوئی شخص کسی کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچا تا ہے تو دوسرے
کو بھی ایسا کرنے کا حق حاصل ہو جاتا ہے اور جب وہ جوابا ایسا ہی کرے گا تو پھر یہ
نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ جس مذہب کی توہین کر رہا ہے وہ اپنی جگہ صحیح ہے یا غلط
دونوں فریق جوابی کارروائی کرنے کا یکساں حق رکھتے ہیں.پس نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ
اگر مذہبی جرم کا ارتکاب ہوا ہے تو اس کا بدلہ بھی اسی نوعیت کا لیا جائے گا.یہ بالکل
اسی طرح ہے جیسے کسی کو جسمانی اذیت دی گئی ہو تو اس کا بدلہ بھی جسمانی اذیت ہی
ہوگا.اگر چہ شرط یہ ہوگی کہ بدلہ لینے میں کسی قسم کی کوئی زیادتی روا نہ رکھی جائے.قرآن مجید میں مذہبی اہانت کا ذکر حضرت مریم اور حضرت مسیح علیہما السلام کے
تعلق میں بھی آیا ہے.وَبِكُفْرِهِمْ وَ قَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهِتَانًا عَظِيمًا ( سورة النساء آیت ۱۵۷)
ترجمہ.نیز ان کے کفر کی وجہ سے اور ان کے مریم کے خلاف ایک بہت
47
Page 60
بڑے بہتان کی بات کہنے کی وجہ سے.اس آیت میں حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانہ کے یہود کے اس مذموم اور
توہین آمیز موقف کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو اب تاریخ کا حصہ بن چکا ہے.یہود
نے یہ الزام لگایا تھا کہ حضرت مریم نعوذ باللہ پاک دامن نہیں ہیں لہذا حضرت مسیح کی
ولادت بھی قابل اعتراض ہے.یہود کا یہ الزام ان دونوں مقدس وجودوں کی شان
میں سخت تو ہین اور گستاخی پر مشتمل ہے.یہود کے اس الزام کو اس آیت میں
بہتان عظیم یعنی بہت ہی بڑا اتہام قرار دیا گیا ہے اور اس انتہائی اذیت ناک گستاخی
اور توہین کی بہت سخت الفاظ میں مذمت کی گئی ہے.مگر حیران کن بات یہ ہے کہ اس
گستاخی کی کوئی جسمانی سزا تجویز نہیں کی گئی ہے.یہ بات بھی دلچسپی سے خالی نہیں ہے کہ یہود کی مذمت تو اس لئے کی گئی کہ
انہوں نے حضرت مریم اور حضرت مسیح علیہما السلام کی توہین کی تھی مگر عیسائیوں کی
مذمت خود اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرنے پر کی گئی ہے.عیسائیوں کی گستاخی یہ
ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ خدا کے ہاں اس کی بیوی کے ذریعہ جو انسانوں میں سے تھی
ایک بیٹا پیدا ہوا.قرآن مجید نے عیسائیوں کے اس الزام کو شر عظیم قرار دیا ہے لیکن
اس کے باوجود کسی قسم کی کوئی جسمانی سزا مقرر نہیں کی گئی اور نہ ہی کسی انسانی عدالت
کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ خدا کی شان میں ایسی سخت گستاخی کرنے والوں کو کوئی سزا
دے.قرآن مجید کی وہ آیت جس میں اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرنے پر مسیحیوں
کی مذمت کی گئی ہے یہ ہے.مَالَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلا لا بَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ
الَّا كَذِبًاه
( سورة الكهف آیت ۶ )
ترجمہ.ان کو اس کا کچھ بھی علم نہیں ، نہ ہی ان کے آباؤ اجداد کو تھا.48
Page 61
بہت بڑی بات ہے جو ان کے مونہوں سے نکلتی ہے.وہ جھوٹ کے سوا
کچھ نہیں کہتے.اب میں آخر میں ایک انتہائی نازک اور حساس مسئلہ کی طرف آتا ہوں.یہ
معاملہ اس لحاظ سے بھی نازک ہے کہ آج کل کے مسلمان توہین رسالت کے متعلق
پہلے سے بڑھ کر حساس واقع ہوئے ہیں.تاریخ اسلام میں مذہبی توہین کا ایک واقعہ
ملتا ہے جو اس قدر سنگین ہے کہ خود قرآن کریم نے اسے ریکارڈ کیا ہے.یہ واقعہ عبد اللہ بن اُبی بن سلول کے متعلق ہے جسے تاریخ اسلام میں
رئیس المنافقین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے.ایک جنگی مہم سے واپسی کے دوران
عبداللہ بن اُبی بن سلول نے بعض دوسرے لوگوں کی موجودگی میں کہا کہ جونہی وہ
مدینہ پہنچے گا تو وہاں کا سب سے معزز انسان وہاں کے سب سے ذلیل انسان کو مدینہ
سے نکال باہر کرے گا.قرآن کریم اس واقعہ کا ذکر ان الفاظ میں کرتا ہے.يَقُولُونَ لَمِنْ رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْآعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ
وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ (سورة المنافقون آیت ۹)
ترجمہ.وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینہ کی طرف لوٹیں گے تو ضرور وہ جوسب
سے زیادہ معزز ہے اسے جو سب سے زیادہ ذلیل ہے اس میں سے نکال
باہر کرے گا.حالانکہ عزت تمام تر اللہ اور اس کے رسول کی ہے اور
مومنوں کی.لیکن منافق لوگ جانتے نہیں.اس فقرہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کی گئی گستاخی کو صحابہ کرام
رضوان اللہ میم خوب سمجھ گئے تھے.اور اس جسارت پر ان کا خون غصے سے کھول رہا
تھا.انہیں اس کا اس قدر رنج تھا کہ اگر ان کو اجازت ہوتی تو وہ یقینا عبداللہ بن
49
49
Page 62
أبي بن سلول کی تکا بوٹی کر کے رکھ دیتے.مستند روایات میں بیان ہے کہ اس واقعہ
پر صحابہ اس قدر مشتعل تھے کہ خود عبد اللہ بن اُبی بن سلول کے بیٹے نے آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے باپ کو قتل کرنے کی اجازت مانگی.اس نے عرض کی کہ اگر کسی اور نے میرے باپ کو قتل کر دیا تو ایسا نہ ہو کہ بعد میں
جہالت کی وجہ سے میرے دل میں اپنے باپ کے قاتل کے خلاف انتقام کا جذبہ
بھڑک اٹھے.اپنی یا اپنے قریبی رشتہ داروں کی معمولی سی بے عزتی کا انتقام لینا
صدیوں سے عربوں کی تہذیب کا حصہ تھا.انتقام کا یہی رواج تھا جو غالبا اس کے
ذہن میں تھا.لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف ایسا کرنے کی اجازت
دینے سے انکار کر دیا بلکہ صحابہ میں سے کسی اور کو بھی اجازت نہ دی کہ اس منافق کو
کسی قسم کی کوئی سزا دے.(ابن اسحاق بحوالہ سیرۃ النبی مصنفہ ابن ہشام حصہ سوم )
چنانچہ اس جنگی مہم سے واپس مدینہ آ کر عبدالله بن أبي بن سلول بلاخوف وخطر
زندگی بسر کرتا رہا.بالآ خر جب وہ اپنی طبعی موت مرا تو سب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے
کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد اللہ بن اُبی بن سلول کے بیٹے
کو اس کے باپ کے کفن کے لئے اپنا کرتہ عطا فرمایا.یہ دراصل
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے لئے خدا کی مغفرت مانگنے کا ایک نرالا انداز
تھا.صحابہ کرام کے دلوں میں اس وقت یہ خواہش ضرور پیدا ہوئی ہوگی کہ کاش وہ اپنا
سب کچھ دے کر عبد اللہ بن اُبی بن سلول کے بیٹے سے وہ کر نہ اپنے لئے حاصل کر
لیں.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پر اکتفا نہیں کی بلکہ اس کی نماز جنازہ بھی
خود پڑھانے کا فیصلہ فرمایا.اس فیصلہ نے اکثر صحابہ کو یقینا حیران کر دیا ہوگا کیونکہ وہ
عبد اللہ بن اُبی بن سلول کے اس سنگین جرم کو معاف نہیں کر پائے تھے جس کا ذکر
اوپر گزر چکا ہے.آخر صحابہ کرام رضوان الله علیہم کے خاموش جذبات کی ترجمانی
50
60
Page 63
کا کام حضرت عمرؓ نے کر دیا.بیان کیا جاتا ہے کہ جب حضرت رسول کریم
صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھانے کے لئے تشریف لا رہے تھے تو حضرت عمر
اچانک آگے بڑھ کر حضور کے رستے میں کھڑے ہو گئے.آپ نے حضور صلی اللہ علیہ
وسلم کی خدمت میں درخواست کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فیصلے پر نظر ثانی
فرمائیں.یعنی عبد اللہ بن اُبی بن سلول کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں.اس موقع پر
حضرت عمرؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کی اس آیت کا حوالہ بھی دیا
جس میں بعض منافقین کے متعلق شفاعت قبول نہ کئے جانے کا ذکر ہے کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لئے ستر مرتبہ بھی دعائے مغفرت کریں تو بھی قبول
نہیں کی جائے گی.ضمنا یہاں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ستر سے یہاں لفظاً ستر کا عدد
مراد نہیں ہے.عربوں کے محاورہ کے مطابق ستر کثرت پر بھی دلالت کرتا ہے اور
یہاں انہی معنوں میں استعمال ہوا ہے.بہر حال حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت عمرؓ کی بات سن کر مسکرائے اور فرمایا.عمر میرا راستہ چھوڑ دو میں خدا کا رسول
ہوں اور تم سے بہتر جانتا ہوں.اگر خدا میرے ستر مرتبہ مغفرت طلب کرنے پر بھی
ایسے لوگوں کو معاف نہیں کرے گا تو میں ستر سے زیادہ مرتبہ ان کے لئے استغفار
کروں گا.بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن اُبی بن سلول کی نماز
جنازہ پڑھائی.(بخاری کتاب الجنائز باب الکفن)
جو لوگ شاتم رسول کے لئے موت سے کم کسی سزا پر راضی نہیں ہوتے یہاں تک
که چیخ چیخ کر ان کے گلے بیٹھ جاتے ہیں کیا ان کا منہ بند کرنے کے لئے یہی ایک
واقعہ کافی نہیں؟ یقینا ایسا مذہب ہی دنیا بھر کے مذاہب کے مابین امن قائم کرنے
کے دعوی کا حق رکھتا ہے.51
Page 64
مذاہب کا باہمی تعاون
فرمایا:
مذاہب کے باہمی تعلقات میں اسلام ایک قدم اور آگے بڑھاتا ہے.چنانچہ
وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا و
سلط
تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَان " وَاتَّقُوا اللهَ *
إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ
(سورۃ المائدہ آیت ۳)
ترجمہ.اور تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس وجہ سے کہ انہوں نے تمہیں
مسجد حرام سے روکا تھا اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم زیادتی کرو.اور
نیکی اور تقویٰ میں ایک دوسرے سے تعاون کرو اور گناہ اور زیادتی کے
کاموں) میں تعاون نہ کرو.اور اللہ سے ڈرو.یقینا اللہ سزا دینے میں
بہت سخت ہے.پس قرآن کریم مسلمانوں کو ایسے دشمنوں کے ساتھ بھی نا انصافی کرنے کی
اجازت نہیں دیتا جو مذہبی عناد کی وجہ سے ان پر حملہ آور ہوئے ہوں.اور ایسے
غیر
مسلم جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف کبھی جنگ نہیں کی ان کا ذکر کرتے ہوئے
قرآن کریم مومنوں کو ہدایت دیتا ہے.ط
هه = ط
عَسَى اللَّهُ أَنْ يُجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَّوَدَّةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ
وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ O لا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَن الَّذِينَ لَمْ يُقْتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ
يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارَكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُقْسِطِينَ
(سورۃ الممتحنہ آیات ۸-۹)
ترجمہ.قریب ہے کہ اللہ تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان جن میں
بعض سے تم باہمی عداوت رکھتے ہو محبت ڈال دے اور اللہ ہمیشہ قدرت
529
52
Page 65
رکھنے والا ہے اور اللہ بہت بخشنے والا ( اور ) بار بار رحم کرنے والا ہے.للہ تمہیں ان سے منع نہیں کرتا جنہوں نے تم سے دین کے معاملہ میں قتال
نہیں کیا اور نہ تمہیں بے وطن کیا کہ ان سے نیکی کرو اور ان سے انصاف
کے ساتھ پیش آؤ.یقیناً اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے.مسلمانوں کو یہ تعلیم بھی دی گئی ہے کہ وہ توحید کے پیغام کی اشاعت کے لئے
اہل کتاب کو بھی تعاون کے لئے بلائیں.کیونکہ توحید کا عقیدہ تو سب میں مشترک
ہے.قرآن کریم کی درج ذیل آیت کا مفہوم بھی یہی ہے کہ اس قدر مشترک پر زور
دیا جائے اور مقصد یہ ہے کہ ان امور پر اکٹھے ہو کر ایسے پروگرام بنائے جائیں جن
سے بنی نوع انسان کو فائدہ پہنچے نہ کہ اختلافی مسائل کو ہوا دے کر فساد پیدا کیا
جائے.قُلْ يَأَهْلَ الْكِتَبِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا
نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا
اشهدوا بأنا مسلمون
(سورۃ آل عمران آیت ۶۵)
ترجمہ.تو کہہ دے، اے اہل کتاب! اس کلمہ کی طرف آجاؤ جو ہمارے
اور تمہارے درمیان مشترک ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں
گے.اور نہ ہی کسی چیز کو اس کا شریک ٹھہرائیں گے.اور ہم میں سے
کوئی کسی دوسرے کو اللہ کے سوا رب نہیں بنائے گا.پس اگر وہ پھر
جائیں تو کہہ دو کہ گواہ رہنا کہ یقینا ہم مسلمان ہیں.حاصل بحث
کیا دنیا بھر کے مذاہب امن عالم کے قیام میں کوئی بامعنی کردار ادا کر سکتے ہیں؟
53
Page 66
لیکن ذرا ٹھہریئے پہلے تو یہ جائزہ لینا ہو گا کہ مختلف مذاہب نے اپنے متبعین اور دیگر
فرقوں کے درمیان امن قائم کرنے میں کیا کردار ادا کیا ہے.کیا مختلف مذاہب
(جب تک ہیں ) کبھی باہم امن کے ساتھ رہنا سیکھ سکتے ہیں؟ اگر مادیت کے بڑھتے
ہوئے اثرات کو دیکھا جائے اور اس طرف نظر ڈالی جائے کہ دنیا کس طرح روحانی
لذات کی بجائے جسمانی اور جنسی لذات کو اہمیت دے رہی ہے تو یہ یقین ہونے لگتا
ہے کہ مذہب کا کردار اس صورت حال میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا لہذا اسے یکسر
نظر انداز کر دینا چاہئے.لیکن مجھے افسوس ہے کہ میں اس نتیجہ سے متفق نہیں ہوسکتا.میرے نزدیک
مذہب امن عالم کے قیام میں ایک کردار ادا کرتا رہے گا اور بدقسمتی سے وہ انتہائی منفی
نوعیت کا کردار ہوگا سوائے اس کے کہ جملہ مذاہب اپنے داخلی اور خارجی رویوں
میں کوئی خوش آئند تبدیلی پیدا کر لیں.مذہب کو تو قیام امن میں بڑا اہم کردار ادا کرنا
چاہئے تھا.اس کا کام تو یہ تھا کہ مختلف مذاہب اور فرقوں کے پیروؤں کے درمیان
غلط فہمیوں کے ازالے، شائستگی کی ترویج اور جیو اور جینے دو کے اصول کے نفاذ کے
سلسلہ میں اپنا فرض ادا کرتا.مگر بدقسمتی یہ ہے کہ عصر حاضر میں فروغ امن کے لئے
مذاہب نے اگر کہیں کوئی کردار ادا کیا بھی ہے تو وہ بہت ہی خفیف اور معمولی نوعیت کا
ہے.اس کے برعکس فساد اور خونریزی کو جنم دینے کے لحاظ سے مذہب آج بھی ایک
بڑی فعال طاقت ہے.دکھ اور مصائب پیدا کرنے میں مذہب کی طاقت کو کبھی کم
نہیں سمجھنا چاہئے.پس اگر ہم دنیا میں امن کے خواہاں ہیں تو اس معاملے میں جو
نقائص موجود ہیں انہیں دور کرنا ہوگا.عالمی امن کا کوئی خواب اس اہم مسئلے کو حل کئے
بغیر شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا.اندرونی طور پر بھی مذہب کی طاقت کو منفی رنگ میں
استعمال کیا جا سکتا ہے.ایک ہی مذہب کے متبعین کے مذہبی جذبات کو اسی مذہب
54
Page 67
"
سے وابستہ کچھ لوگوں کے خلاف بھڑکا یا جا سکتا ہے.ان پر مصائب و آلام کے پہاڑ
توڑے جا سکتے ہیں.صرف اس لئے کہ بدقسمتی سے وہ اقلیت میں ہیں.مسلمانوں کی ساری تاریخ ایسے بھیانک اور بدنما واقعات سے بھری پڑی ہے
جب اسلام کو جو امن و آشتی کا مذہب ہے دوسرے بے گناہ مسلمانوں کے امن و چین
کو تباہ و برباد کرنے کے لئے استعمال کیا گیا.وہ مظلوم لوگ بلاشبہ مسلمان ہی تھے
صرف انکا مسلک وہ نہیں تھا جو اکثریت ان پر ٹھونسنا چاہتی تھی.تاریخ اسلام سے یہ
بات ثابت ہے کہ خود مسلمانوں پر اسلام کے نام پر ظلم و ستم توڑے گئے ہیں.مسلمانوں نے جتنی صلیبی جنگیں عیسائیوں کے خلاف لڑی ہیں وہ تعداد اور شدت میں
ان مقدس جنگوں سے بہت کم ہیں جو چودہ سو سال میں مسلمانوں نے مسلمانوں
کے خلاف لڑی ہیں.اور یہ داستان ابھی اپنے اختتام کو نہیں پہنچی.پاکستان میں
احمدی مسلمانوں کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ شیعہ اقلیت کے خلاف اکثر ہوتا
رہتا ہے وہ اس تلخ حقیقت کی طرف ہماری توجہ مبذول کروانے کے لئے کافی ہے.یہ صورت حال متنبہ کر رہی ہے کہ جو شر انگیز مسئلہ مدتوں پہلے ختم ہو جانا چاہئے تھا وہ
آج بھی جوں کا توں موجود ہے.عیسائیوں نے بھی خود عیسائیوں پر ظلم توڑے ہیں.اگر یورپ اور امریکہ کی
تاریخ کے اوراق میں مدفون مذہبی ظلم وستم کے واقعات امتداد زمانہ کی وجہ سے
ذہنوں سے محو ہو گئے ہوں تو صرف آئر لینڈ میں جاری مذہبی و سیاسی کشمکش کو ایک نظر
دیکھ لینا کافی ہوگا.دیگر خطوں میں بھی عیسائیت میں اندرونی فرقہ وارانہ کشمکش کے مخفی
خطرات موجود ہیں اگر چہ فی الحال یہ علاقے بعض دیگر نوعیت کے جھگڑوں اور
تنازعات میں الجھے ہوئے ہیں.ہندوستان میں ہندو مسلم فسادات، نائیجیریا میں
عیسائیوں اور مسلمانوں کی کشمکش، مشرق وسطی میں یہود اور مسلمانوں کی جنگیں یا
55
Page 68
یہود و نصاریٰ کے نازک اور حساس اقتصادی و سیاسی تعلقات اور ان میں بگاڑ کا مخفی
رجحان دراصل انہی پوشیدہ خطرات کی نشان دہی کرتے ہیں.یہ خطرات مذہبی دنیا
میں خوابیدہ آتش فشاں پہاڑوں کی طرح ہیں جو کسی بھی وقت پھٹ سکتے ہیں.ان
مسائل کے متعلق ذہنی رویوں میں اصلاح کرنے کی اہمیت اتنی واضح ہے کہ اس پر
مزید زور دینے کی ضرورت نہیں ہے.اسلام ان مسائل کا کیا حل پیش کرتا ہے؟ اس
پر تفصیلی بحث گزر چکی ہے.ذیل میں اس بحث کے اہم نکات کو مختصر طور پر بیان کر کے
میں اس حصہ کو ختم کرتا ہوں.(۱) دنیا کے تمام مذاہب کو خواہ وہ اسلام کو سچا مذہب تسلیم کرتے ہیں یا نہیں اس
بنیادی اسلامی اصول پر عمل پیرا ہونا چاہئے کہ اندرونی فرقہ وارانہ جھگڑوں اور
دوسرے مذاہب کے ساتھ تنازعات حل کرنے کے لئے طاقت اور جبر کے استعمال
کی کسی صورت میں بھی اجازت نہیں دی جائے گی.ہر شخص کو مذہبی آزادی کی ضمانت
دی جائے گی.مذہبی آزادی میں کسی شخص کو کوئی مذہب اختیار کرنے یا نہ کرنے اپنے
عقیدہ کا اعلان کرنے ، اس پر عمل اور اس کی تبلیغ کرنے، کسی عقیدہ کو غلط کہنے یا اسے
ترک کرنے یا اپنا عقیدہ بدلنے کی پوری آزادی ہوگی اور اس آزادی کا پورا تحفظ کیا
جائے گا.(۲) تمام اہل مذہب کے لئے کم از کم اس اسلامی اصول کی پابندی لازمی ہوگی
کہ وہ تمام بانیان مذاہب اور ہر مذہب کے بزرگوں کا احترام کریں.دیگر مذاہب
خواہ سچائی کے اسلامی تصور اور اس کی آفاقیت کے قائل نہ بھی ہوں، یہودیت،
عیسائیت، بدھ ازم، کنفیوشس ازم، ہندو ازم ، زرتشت ازم وغیرہ کے نقطہ نظر سے خواہ
باقی مذاہب جھوٹے ہی کیوں نہ ہوں اور خدا سے ان کا کوئی بھی تعلق نہ ہو تب بھی
ہر مذہب کے مقدس لوگوں کا احترام کرنا ان کے لئے لازمی ہوگا.اگر چہ ایسا کرتے
56
60
Page 69
وقت انہیں اپنے اصولوں کے بارہ میں کسی قسم کا سمجھوتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی
کیونکہ باہمی احترام تو بنیادی انسانی حقوق سے تعلق رکھنے والا معاملہ ہے.ہر انسان
کے اس بنیادی انسانی حق کو تسلیم کرنا ضروری ہے کہ اس کے مذہبی احساسات اور
جذبات کو کسی صورت بھی ٹھیس نہ پہنچائی جائے اور اس کی دل آزاری نہ ہو.(۳) یہ یاد رکھنا چاہئے کہ پیشوایان مذاہب کے احترام کے اصول کو کسی قومی یا
بین الاقوامی قانون کے ذریعہ نافذ نہیں کیا جا سکتا.مذہبی تو ہین کو ایک ذلیل حرکت
قرار دینے کے لئے اور اس کی حوصلہ شکنی کے لئے رائے عامہ کو بیدار کرنا چاہئے
تا کہ وہ ایسے غیر شائستہ ، نامعقول اور قبیح فعل کی مذمت کرے.(۴) اس صدی کے اوائل میں جماعت احمدیہ نے جس طرز پر بین المذاہب
کا نفرنسوں کے انعقاد کا سلسلہ شروع کیا تھا ایسی کانفرنسوں کے وسیع پیمانے پر انعقاد
کی حوصلہ افزائی ہونی چاہئے اور انہیں رواج دینا چاہئے.ایسی کانفرنسوں کی جو
خصوصیات ہونی چاہئیں وہ خلاصہ درج ذیل ہیں.(۱) تمام مقررین کو چاہئے کہ وہ اپنے اپنے مذہب کی دلکش اور امتیازی خوبیاں بیان
کریں اور دوسرے مذاہب پر کیچڑ نہ اچھالیں.(ب) مقررین کو چاہئے کہ وہ پوری ایمانداری اور اخلاص سے دوسرے مذاہب کی
خوبیوں کو تلاش کرنے کی کوشش کریں اور پھر انہیں اپنی تقاریر میں بیان کریں اور یہ
بھی بتائیں کہ وہ ان خوبیوں سے متاثر ہیں.(ج) مقررین کو دیگر بانیان مذاہب اور مذہبی رہنماؤں کی سیرت اور کردار کو
خراج تحسین پیش کرنا چاہئے.مثلاً ایک یہودی مقرر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
امتیازی اوصاف بیان کر سکتا ہے یعنی ایسے اوصاف جن کی سب لوگ اپنے مذہبی
عقائد سے کوئی سمجھوتہ کئے بغیر تعریف کر سکتے ہیں.ایسے ہی ایک مسلمان مقرر
57
Page 70
حضرت کرشن علیہ السلام کے متعلق تقریر کر سکتا ہے.ایک ہند و حضرت عیسی علیہ السلام
اور بدھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت بیان کر سکتا ہے وغیرہ وغیرہ.اس صدی کی
تیسری دہائی میں جماعت احمدیہ کے زیر اہتمام ہندوستان میں ہندو مسلم تعلقات کو
بہتر بنانے کے لئے ایسی مفید اور مقبول کا نفرنسیں منعقد ہوا کرتی تھیں.(د) مندرجہ بالا تجویز (ج) کے متعلق کسی قسم کے استثناء کے بغیر اس امر کا خیال رکھا
جانا بے حد ضروری ہوگا کہ مختلف مذاہب اور فرقوں کے مابین تبادلہ خیالات کے وقت
مذہبی بحث و مباحثہ کے تقدس کی پوری حفاظت کی جائے.مذہبی تبادلہ خیالات کی یہ
کہہ کر مذمت نہیں کی جانی چاہئے کہ اس سے نقض امن کا اندیشہ ہوگا.اگر بحث کا
طریق اور انداز غلط ہے تو صرف اس غلط طریق اور غلط انداز کی مذمت ہونی چاہئے
نہ کہ بحث کو فی ذاتہ غلط قرار دے دیا جائے.اپنے خیالات کا آزادانہ اظہار ایک
انتہائی اہم بنیادی انسانی حق ہے.بقائے اصلح یعنی موزوں اور اعلیٰ چیز کی بقا کے لئے
یہ بے حد ضروری ہے کہ کسی قیمت پر بھی اس اصول سے سمجھوتہ نہ کیا جائے.(ر) اختلافات کے دائرہ کو محدود کرنے اور باہمی اتفاق کے امکانات کو بڑھانے
کے لئے اس اصول کو تسلیم کرنا بے حد ضروری ہے کہ تمام مذاہب اپنی بحث کو اپنے
اور دوسرے مذاہب کے بنیادی تک محدود رکھیں گے.قرآن کریم کا یہ اعلان کہ
تمام مذاہب اپنے آغاز میں یکساں تھے بڑی اہمیت کا حامل ہے اور اس میں عظیم
حکمتیں پوشیدہ ہیں.تمام مذاہب کو اپنے اور تمام بنی نوع انسان کے فائدہ کی خاطر
قرآن کریم کے اس اعلان کا بغور مطالعہ کرنا چاہئے اور اس کی سچائی جانچنے کے لئے
تحقیق کرنی چاہئے.(۵) مشترکہ مفاد کے تمام منصوبوں اور سکیموں میں تعاون کو فروغ دیا جائے اور
اس کی زیادہ سے زیادہ حوصلہ افزائی کی جائے مثلاً رفاہ عامہ کے منصوبوں پر عیسائی،
مسلمان، ہندو اور یہودی سب مل جل کر کام کر سکتے ہیں.58
Page 71
گزشتہ زمانوں کے حکماء اور اولیاء نے بنی نوع انسان کے اتحاد کے جو خواب
دیکھے تھے صرف اسی صورت میں ہم انہیں حقیقت کا روپ دینے کی امید کر سکتے ہیں.وہ خواب جن میں انہوں نے مذہبی، معاشی، سیاسی غرضیکہ ہر دائرہ میں بنی نوع انسان
کو ایک جھنڈے تلے جمع کرنے کا تصور باندھا تھا.59
59
Page 73
معاشرتی امن...عصر حاضر کا معاشرتی نظام...دو قسم کے معاشرتی ماحول
ید....مادہ پرست معاشرہ کا انجام
حمد....حیات بعد الموت کا انکار
مادہ پرست معاشرہ کی چار خصوصیات
اعمال کی جوابدہی کا تصور
اسلامی معاشرہ کا مخصوص ماحول...اسلامی معاشرہ کے بنیادی اصول
عفت اور پاکدامنی
ے پردہ اور اس کی حقیقت
حقوق نسواں کے ایک نئے دور کا آغاز
عورتوں کے لئے مساوی حقوق......تعد وازدواج
عمر رسیدہ افراد کی دیکھ بھال
مستقبل کی نسلیں
بے مقصد اور فضول مشاغل کی حوصلہ شکنی
بے من
61
Page 74
29
62
خواہشات پر قابو پانا
عهد و پیمان اور معاہدات کا احترام
برائی کا خاتمہ.ایک اجتماعی ذمہ داری.......اوامر و نواہی......اوامر....نواہی...اسلام نسل پرستی کورڈ کرتا ہے
Page 75
و
1000
إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَان وَ إِيْتَأَيَّ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (سورة النحل آیت (۹)
ترجمہ.یقینا اللہ عدل کا اور احسان کا اور اقربا پر کی جانے والی عطا
کی طرح عطا کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی اور نا پسندیدہ باتوں اور
بغاوت سے منع فرماتا ہے تا کہ تم عبرت حاصل کرو.اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوَ وَزِينَةٌ وَ تَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَ تَكَاثر
هو
فِي الْأَمْوَالِ وَإِلَّا وَلَادِ كَمَثَلِ غَيْتَ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ
وہ لگا وہ
ط
لا
فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَ مَغْفِرَةٌ
مِّنَ اللهِ وَرِضْوَانُ وَمَا الْحَيَوةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِه
(سورۃ الحدید آیت ۲۱)
28
ترجمہ.جان لو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل کود اور نفس کی خواہشات کو
پورا کرنے کا ایسا ذریعہ ہے جو اعلیٰ مقصد سے غافل کر دے اور سج
د صح اور باہم ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے اور اموال اور اولاد میں
ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرنا ہے.( یہ زندگی ) اس بارش
کی مثال کی طرح ہے جس کی روئیدگی کفار (کے دلوں ) کو لبھاتی
ہے.پس وہ تیزی سے بڑھتی ہے.پھر تو اسے زرد ہوتا ہوا دیکھتا
ہے.پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے اور آخرت میں سخت عذاب
( مقدر) ہے نیز اللہ کی طرف سے مغفرت اور رضوان بھی.جبکہ دنیا
کی زندگی تو محض دھو کے کا ایک عارضی سامان ہے.63
Page 77
اب ہم اس سوال کی طرف آتے ہیں کہ عصر حاضر میں معاشرتی امن کو قائم
کرنے میں اسلام کا کیا کردار ہے.عصر حاضر کا معاشرتی نظام
عدم
بدقسمتی سے آج کے معاشرہ میں لوگوں کے اخلاق سے مذہب کا اثر تیزی سے مٹتا
جا رہا ہے.حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جارہے ہیں.لوگ کسی نہ کسی طرح مذہبی
فرائض سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں اور مذہبی پابندیوں سے دامن چھڑانے کا
یہ رجحان بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے.لیکن جہاں ایک طرف مذہبی اور اخلاقی اقدار سے
لا پرواہی برتی جا رہی ہے وہاں اس کے ساتھ ساتھ معاشرہ میں افراتفری اور
م تحفظ کے بڑھتے ہوئے احساس کے باعث خوف و ہراس کی کیفیت بھی جنم لے
رہی ہے.اس حی و قیوم خدا پر ایمان تیزی سے اٹھتا چلا جا رہا ہے جو نہ صرف
انسان کی تقدیر بنانے والا ہے بلکہ وہی یہ حق بھی رکھتا ہے کہ ہمارے لئے زندگی کے
طور طریقے اور آداب وضع فرمائے.اس صورت حال
کو مختصر طور پر قرآن کریم یوں
بیان فرماتا ہے.ظَهَرَ الفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ( سورۃ الروم آیت ۴۲)
ترجمہ.فساد خشکی پر بھی غالب آ گیا اور تری پر بھی.انیسویں صدی کے آغاز تک مغرب میں عیسائیت کا غلبہ تھا اور عیسائیوں کے
اخلاق اور کردار پر عیسائیت کی گرفت بڑی مضبوط اور مؤثر تھی مگر افسوس کہ اب یہ
منظر تبدیل ہو چکا ہے.سائنٹفک سوشلزم اور تیز رفتار سائنسی اور مادی ترقی کے زیر اثر
ایک ایسی تہذیب ابھری ہے جس نے عیسائیت کو قدم بقدم پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا ہے
65
Page 78
اور لوگوں کے معاشرتی اخلاق کی تشکیل میں عیسائیت کا کردار رفتہ رفتہ معدوم ہوتا چلا
گیا ہے.آج صورت حال یہ ہے کہ مغرب میں لوگوں کے اخلاق اور کردار پر
عیسائیت کا محض اتنا ہی نقش باقی ہے جتنا کہ اکثر مسلم ممالک میں رہنے والے
مسلمانوں پر اسلام کا.افسوس یہ ہے کہ باقی دنیا میں بھی سماجی اور اخلاقی انحطاط کا
یہی عالم ہے.مختلف ممالک میں مہاتما بدھ ، حضرت کنفیوشس اور حضرت کرشن کے
ماننے والے تو بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں مگر بدقسمتی یہ ہے کہ بدھ ازم،
کنفیوشس ازم اور ہندو ازم کہیں نظر نہیں آتے.یعنی سمندر چاروں طرف موجود ہے
لیکن پیاس بجھانے کو ایک قطرہ بھی میسر نہیں.اگر کسی معاشرہ سے مذہبی یا روایتی اخلاقی قدریں اٹھ جائیں تو پھر نئی نسل اپنے
روایتی ورثہ کو آنکھیں بند کر کے قبول نہیں کیا کرتی.اس کے لئے یہ قدریں بے معنی
ہو کر رہ جاتی ہیں.ایسی نسل کو لازما ایک ایسے نازک عبوری دور اور بحران میں سے
گزرنا پڑتا ہے جس میں سوائے مایوس کن خلا کے اور کچھ بھی نہیں ہوتا.نہ ہی کوئی
اخلاقی تعلیم ان کے پاس ہوتی ہے.تب جستجو کا ایک نیا سفر شروع ہوتا ہے.لیکن
منزل کا نہ کچھ پتہ ہوتا ہے اور نہ انجام کی کچھ خبر..عین ممکن ہے کہ اس سفر میں انہیں کوئی بہتر ضابطہ اخلاق مل جائے مگر یہ بھی ممکن
ہے کہ یہ جستجو انسان کو مکمل ابتری اور اخلاقی طوائف الملو کی کی طرف لے جائے.جو
حالات مجھے دکھائی دے رہے ہیں ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ بدقسمتی سے عصر حاضر کا
معاشرہ یہی مؤخر الذکر راستہ اختیار کر چکا ہے.آج دنیا کے سبھی معاشرے خواہ وہ
مشرقی ہوں یا مغربی مذہبی ہوں یا غیر مذہبی انقلابات کی زد میں ہیں اور ان کے
بداثرات نے ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے.مگر المیہ یہ ہے کہ آج کا
انسان اس بڑھتی ہوئی اخلاقی عفونت کے متعلق اتنا فکر مند نہیں جتنا مادی فضاؤں کی
66
99
Page 79
آلودگی کے متعلق پریشان ہے.قرآن کریم ایک ایسے ہی پر آشوب دور کا ذکر کرتے
ہوئے فرماتا ہے.وَالْعَصْرِهِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْره الا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ وَ
تَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِه (سورۃ العصر آیات ۲ تا ۴)
ترجمہ.زمانے کی قسم ! یقیناً انسان ایک بڑے گھاٹے میں ہے.سوائے
ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے اور حق پر قائم
رہتے ہوئے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی اور صبر پر قائم رہتے ہوئے
ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی.استحصال، دھوکہ دہی ، منافقت، خود غرضی ، ظلم، لالچ ، لذت کی دیوانہ وار تلاش،
بدنظمی، بدعنوانی، چوری چکاری ، ڈاکہ زنی، حقوق انسانی کی خلاف ورزی،
فریب کاری، دغابازی، احساس ذمہ داری کا فقدان اور باہمی احترام و اعتماد کی کمی
آج کے جدید معاشروں کی امتیازی خصوصیات ہیں.ظاہری تہذیب کی جھوٹی
ملمع کاری زیادہ دیر تک اس بدنمائی کو چھپا نہیں سکتی جو اب کھل کر سامنے آ رہی ہے.یہ کہنا تو غلط ہوگا کہ اس قسم کی انسانی کمزوریاں پہلے زمانوں میں نہیں ہوتی تھیں بلکہ
حقیقت یہ ہے کہ ماضی کی بہت سی تہذیبیں اپنی صف لیٹے جانے سے پہلے ایسے ہی
امراض کا شکار تھیں.تاریخ انسانی میں نیا منسیا ہو جانے سے پہلے انہیں بھی ایسی ہی
بیماریاں لاحق تھیں اور ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ کوئی خاص قوم یا خطہ ہی ایسا تھا جو اس
قسم کی اخلاقی برائیوں کے باعث ہلاکت کے گڑھے تک جا پہنچا تھا بلکہ یہ وہ تاریخ
ہے جو بار بار دہرائی گئی ہے.آج بھی دنیا کے مختلف معاشرے انحطاط کا شکار ہو رہے ہیں اور سب جگہ اس
انحطاط کی وجوہات بھی خاصی ملتی جلتی ہیں.یک جماعتی آمرانہ نظام رکھنے والے
40
67
Page 80
ممالک کے برعکس نام نہاد آزاد دنیا میں فرد کی آزادی کا بڑھتا ہوا شعور بجائے خود
ایک غیر متوازن رجحان کی شکل اختیار کر رہا ہے.بے لگام آزادی کا یہی رجحان
بڑی حد تک معاشرتی بے راہ روی کا ذمہ دار ہے.جن ممالک میں یک جماعتی آمرانہ نظام مسلط ہے وہاں شخصی آزادی کا بڑھتا ہوا
شعور جبرو استبداد کے پنجہ سے نجات حاصل کرنے کی سخت جدوجہد میں مصروف
ہے.اگر ان ممالک کی مسلح افواج کے بائیں بازو سے تعلق رکھنے والے انتہا پسند
آزادی کی اس لہر کے خلاف نہ اٹھ کھڑے ہوئے تو امکان یہی ہے کہ آزادی کی یہ
جنگ عنقریب کامیابی سے ہمکنار ہو جائے گی.اس آزادی کے حصول کے بعد سابقہ
کمیونسٹ ممالک کی آزاد اور بے لگام فضا میں نوجوان طبقے کے اخلاق پر کیا گزرے
گی اس کے آثار تو کچھ اچھے نظر نہیں آ رہے.اس بے دین اور ملحدانہ خلا میں پوری
دو نسلیں پل کر جوان ہو چکی ہیں.حالت یہ ہے کہ نہ تو کوئی اخلاقی نظام میسر ہے اور
نہ ہی کوئی ایسے راہنما اصول جنکی روشنی میں وہ اپنے کردار کی صحیح تشکیل کر سکیں.ایک
طرف تو ان معاشروں میں ان اخلاقی قدروں کا یکسر فقدان ہے جو کسی بھی روحانی
نظام کی جان ہوا کرتی ہیں اور دوسری طرف لہو ولعب اور عیاشی کے دلدادہ بے مقصد
اور بے لگام مادر پدر آزاد مغربی رجحانات کا ایک سیلاب ہے جو سوویت یونین اور
مشرقی یورپ کی نوجوان نسل کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے جو آگے چل کر اسکی اخلاقی
حالت پر تباہ کن اثرات پیدا کرنے کا موجب بھی بن سکتا ہے.بے دین زندگی کے
اس طویل تجربہ نے جہاں عصر حاضر کو بہت سی برائیوں میں مبتلا کر دیا ہے وہاں اس
امر سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ یہ تجربہ اپنے ہمراہ کچھ فوائد بھی لایا ہے.روس کے
سوشلسٹ ممالک نہ صرف مذہب سے لاتعلق ہو گئے بلکہ انہیں بگڑے ہوئے کٹر
مذہبی عقائد اور نظریات سے بھی چھٹکارا مل گیا.عیسائیت ہو یا اسلام یا ان مذاہب
ا
88
68
Page 81
سے تعلق رکھنے والا کوئی فرقہ سب کے مذہبی تصورات میں قرون وسطی کی سی قدامت
پسندی پائی جاتی تھی.مذہبی عقائد اور فطری حقائق میں جو باہمی تضاد پیدا ہو گیا تھا
اس کا باعث یہی قدامت پسندی تھی.یہ تضادات اتنے گہرے تھے کہ مذہب اور
فطرت دونوں کو بیک وقت درست تسلیم کرنا ناممکن ہو گیا.اس قسم کے مذہبی نظریات
اور حقائق کے مابین اختلافات کی موجودگی میں ذہنی خلفشار سے بچ نکلنے کے لئے
ایک خاص قسم کی ذہنی تربیت کی ضرورت ہے.تضادات کی دنیا میں رہنا اتنا آسان
نہیں سوائے اس کے کہ نسل در نسل لوگ ان کی موجودگی میں پل بڑھ کر جوان ہوں
یہاں تک کہ تضادات کا احساس ہی مٹ جائے.رفتہ رفتہ ایک ایسا وقت بھی آجاتا
ہے کہ مذہبی جماعتیں ان تضادات کی موجودگی میں زندہ تو رہتی ہیں لیکن انہیں یہ
تضادات دکھائی نہیں دیتے.سوشلسٹ انقلاب نے ان ممالک کے رہنے والوں پر
جو اثرات مرتب کئے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انکے ذہن سے کٹر نظریات
دھل کر صاف ہو گئے ہیں اور کج نظری اور کج فہمی کی بیماریاں جاتی رہی ہیں.نتیجہ
ان میں ایک ایسی معصومیت کی جھلک نظر آنے لگی ہے جو منافقت سے چھٹکارا حاصل
کئے بغیر پیدا نہیں ہو سکتی.یہ کہنا تو ابھی بہت قبل از وقت ہوگا کہ آنے والی سخت
جد و جہد کے مشکل وقت میں ایسی معصومیت انہیں کوئی اخلاقی فائدہ بھی دے گی یا
نہیں؟ لیکن ایک بات یقینی ہے کہ ان لوگوں میں آج سچائی کے پیغام کو بلا تعصب
قبول کرنے کے لئے دوسروں سے کہیں زیادہ صلاحیت پیدا ہو چکی ہے.افسوس کہ
باقی دنیا میں شخصی آزادی کے نام نہاد علمبرداروں کے متعلق ہم یہی بات وثوق سے
نہیں کہہ سکتے.بے لگام آزادی کے بڑھتے ہوئے رجحانات کی موجودگی میں یہ نہیں
کہا جا سکتا کہ یہ لوگ بھی قبول حق کے لئے تیار ہیں.واقعہ یہ ہے کہ فرد کی آزادی
کے نام پر عملاً ایک شخص جو چاہے کر سکتا ہے.اس نام نہاد آزادی کے رجحان کا لیڈر
60
69
Page 82
امریکہ ہے جو بڑے وسیع پیمانے پر نہ صرف پہلی دنیا کے یوروپین ممالک بلکہ دوسری
اور تیسری دنیا کے لوگوں پر بھی بری طرح اثر انداز ہو رہا ہے اور اب تو شخصی آزادی
کے اس بگڑے ہوئے نظریے کی صدائے بازگشت سائنٹفک سوشلزم کی نظریاتی سرحد
کے پار بھی بہت دور تک سنائی دے رہی ہے.یہ وہ نظریہ آزادی ہے جو فرد کو
اخلاقیات کی حدود سے آزاد کرتا چلا جارہا ہے.ہم جنس پرستوں، عصمت فروشوں،
بدمعاشوں، نشہ کرنے والوں، بگڑے ہوئے نوجوانوں غرضیکہ ہر قسم کے جرائم پیشہ
افراد کی تعداد بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے اور یہ لوگ روز بروز طاقت پکڑتے جا رہے
ہیں.ان بگڑے ہوئے نو جوانوں کی شوخی کا یہ عالم ہے کہ اگر انہیں سرزنش اور نصیحت
کی جائے اور ٹو کا جائے کہ ایسی حرکتیں نہ کرو تو وہ جوابا پوچھتے ہیں کہ آخر ہم کیوں
ایسا نہ کریں.ایسے نوجوانوں کا یہ رویہ آج معاشرہ کے لئے ایک خطرناک چیلنج بنا ہوا
ہے.دو قسم کے معاشرتی ماحول
قرآن کریم نے معاشرتی نظام کے دو قسم کے ماحول کا ذکر فرمایا ہے.اول.ایسا ماحول یا فضا جس میں بدی کو کھل کھیلنے کی پوری آزادی ہو.دوم.ایسا ماحول جس میں برائی کی نشو ونما کو سختی سے روک دیا جائے.اگر اسلام کی اخلاقی تعلیمات کو یکجائی نظر سے دیکھنے کی بجائے جزواً دیکھا جائے
تو مغربی ذہن کیلئے اسلام کے پیغام اور اس کے فلسفہ کو سمجھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے.پس ضروری ہے کہ اخلاقی تعلیمات کا مطالعہ پورے سماجی ماحول کے تناظر میں کیا
جائے اور معاشرتی ماحول اور اخلاقی تعلیمات پر بحیثیت مجموعی غور کیا جائے.10
70
Page 83
پت جھڑ صرف ایک زرد پتے اور خشک ٹہنی کا نام نہیں ہے.یہ جاننے کیلئے کہ خزاں
کے موسم میں پودوں اور درختوں پر کیا گزرتی ہے ضروری ہے کہ خزاں کے پورے
ماحول کو تصور میں لایا جائے اور اس کے مزاج کو سمجھا جائے.بادل کا ایک ٹکڑا
موسم برسات کی آمد کا پتہ نہیں دیا کرتا.ہر موسم کے اپنے اپنے رنگ ہوتے ہیں.بہار زندگی کی علامت ہے تو خزاں زندگی سے دوری کا دوسرا نام.موسم بہار میں
صرف درجہ حرارت ہی تبدیل نہیں ہوتا بلکہ ساری فضا ہی بدل جاتی ہے اور باد نسیم کا
ایک جھونکا زندگی بخش معلوم ہوتا ہے.معاشرتی نظام بھی موسموں کی طرح الگ الگ
خصوصیات اور اثرات کے حامل ہوتے ہیں.مادہ پرست معاشرہ کا انجام
معاشرتی ماحول کے متعلق اسلام کا نقطہ ء نگاہ بھی یہی ہے.پہلے ہم ایک ایسے
معاشرہ کو لیتے ہیں جو قرآن کریم کی رُو سے غیر اسلامی ہے.اسکا ذکر کرتے ہوئے
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے.اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُوَ وَزِيْنَةٌ وَ تَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَ تَكَاثُرَ فِي
الْأَمْوَالِ وَ الْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْتِ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهِ، ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا
ط
لو لیک
28 0
ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا ، وَفِي الآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ.(سورۃ الحدید آیت ۲۱)
وَمَا الْحَيَوةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ
ترجمہ.جان لو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل کود اور نفس کی خواہشات کو پورا
کرنے کا ایسا ذریعہ ہے جو اعلیٰ مقصد سے غافل کر دے اور سج دھج اور
با ہم ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے اور اموال اور اولاد میں ایک دوسرے
سے بڑھنے کی کوشش کرنا ہے.( یہ زندگی ) اس بارش کی مثال کی طرح
71
Page 84
ނ
ہے جس کی روئیدگی کفار (کے دلوں) کو لبھاتی ہے.پس وہ تیزی
بڑھتی ہے.پھر تو اسے زرد ہوتا ہوا دیکھتا ہے.پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی
ہے اور آخرت میں سخت عذاب ( مقدر) ہے نیز اللہ کی طرف سے
مغفرت اور رضوان بھی.جبکہ دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا ایک عارضی
سامان ہے.مادہ پرستی کے سراب کی اصلیت بیان کرتے ہوئے قرآن کریم فرماتا ہے.وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةِ يَحْسَبُهُ الظَّمَانُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَ ، لَمْ
يَجِدْهُ شَيْئًا وَّ وَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَقَهُ حِسَابَهُ، وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ
---
( سورة النور آیت ۴۰)
ترجمہ.اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال ایسے سراب کی طرح
ہیں جو چٹیل میدان میں ہو جسے سخت پیاسا پانی گمان کرے یہاں تک کہ
جب وہ اس تک پہنچے اسے کچھ نہ پائے.اور اللہ کو اس جگہ پائے پس وہ
اسے اس کا پورا پورا حساب دے اور اللہ حساب چکانے میں تیز ہے.قرآن کریم کے نزدیک مادہ پرستی سراب کی مانند ہے.ایک پیاسا اسے پانی سمجھ
کر اسکی طرف دوڑتا ہے مگر سر اب اس سے آگے کی طرف بھاگتا ہے.یہاں تک کہ
پیاسا اتنا تھک جاتا ہے کہ سراب کا مزید تعاقب نہیں کر سکتا.تب اسے اپنے کئے کی
سزا ملتی ہے اور شدت سے یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ ایک بے معنی اور کھو کھلے مقصد
کے لئے ساری عمر سر گرداں رہا ہے.پھر اچانک یوں لگتا ہے کہ وہ سراب جیسے رک
گیا ہو اور کہ رہا ہو کہ آؤ مجھے پکڑ لو اور دیکھ لو تا کہ تم سمجھ سکو اور تمہیں جلد ہی اندازہ
ہو جائے گا کہ جھوٹی حقیقتوں کے پس پردہ معانی کتنے تلخ ہوا کرتے ہیں.یہ ان
لوگوں کی سزا ہے جو زندگی کی جھوٹی شان وشوکت کے پیچھے بھاگتے ہیں اور
72
Page 85
قرآن کریم کی رو سے یہی وہ انجام ہے جس سے مادہ پرست معاشرے دو چار ہوا
کرتے ہیں.اس کے بالمقابل مذہب ایک ایسا نظریاتی نظام پیش کرتا ہے جس کے مطابق یہ
ور لی زندگی ہی سب کچھ نہیں ہے کہ جس کے ختم ہونے کے ساتھ ہی سب کچھ ختم ہو
جائے بلکہ ایک دوسری زندگی بھی ہے جو اس دنیوی زندگی کے بعد آنے والی ہے.پس اس دنیا میں موت ہمیں ابدی فنا کے گھاٹ نہیں اتارتی بلکہ جیسا کہ اسلام اور دیگر
بہت سے مذاہب یقین دلاتے ہیں موت کے بعد بھی زندگی کا سفر کسی نہ کسی شکل میں
جاری رہتا ہے.اس زندگی کو آنے والی زندگی سے الگ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا.پس اگر یہ سب سچ ہے اور دونوں زندگیاں دراصل ایک ہی تسلسل کے دو نام ہیں تو
اس دنیا کے معاشرتی اثرات کو نظر انداز کرنا انتہائی نادانی کی بات ہوگی.اس زندگی
کے برے اور منفی اثرات آئندہ زندگی میں لا زمنا ایک بیمار روح کو جنم دیں گے.حیات بعد الموت کا انکار
یہاں اخروی زندگی کے متعلق اسلامی فلسفہ پر تفصیلی بحث کا موقع نہیں ہے لیکن
ایک بات کا ذکر ضروری ہے.اسلامی تعلیم کے مطابق اس دنیا کی زندگی ہماری
روحوں پر اس طرح اثر انداز ہوتی ہے جیسے ایک حاملہ کی بیماری رحم مادر میں جنین کو
متاثر کرتی ہے.جس کے نتیجہ میں ممکن ہے کہ بچہ پیدائشی طور پر اتنا معذور ہو کہ اس
کے لئے اس دنیا میں آ کر صحت مند بچوں کے ہمراہ انتہائی بے چارگی کے عالم میں
زندگی بسر کرنا ایک عذاب بن جائے.ظاہر ہے کہ جوں جوں شعور بڑھے گا یہ اذیت
اور بھی زیادہ تلخ اور گہری ہوتی جائے گی.مختصراً یہ کہ اسلام کی تعلیم کے مطابق ہم اپنی
73
الله
Page 86
جنت اور جہنم خود تعمیر کرتے ہیں.اس سیاق و سباق میں یہ امر واضح ہو جانا چاہئے کہ کوئی بھی سماجی نظام جو ایک بے
لگام مادر پدر آزاد اور فساد پر مبنی طرز عمل کو فروغ دیتا ہے وہ بہر حال مسترد کئے جانے
کے لائق ہے خواہ سرسری نظر سے وہ کتنا ہی پرکشش اور جاذب نظر کیوں نہ دکھائی دے.کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ اگلے جہان پر یقین رکھنے والے شوق سے ایسی باتیں
اور دعوی کیا کریں، بھلا مرنے کے بعد بھی کبھی کوئی اس دنیا سے واپس آیا ہے جو ان
دعاوی کی تصدیق یا تکذیب کر سکے.پس کیوں نہ اس دنیا ہی کے مزے لوٹے
جائیں.نو نقد نہ تیرہ ادھار.اور کیوں خواہ مخواہ جانی بوجھی لذتوں کو ان دیکھی لذتوں
پر قربان کیا جائے؟ مادہ پرست لوگ یہ باتیں اسلام کے اس فلسفہ کے جواب میں کیا
کرتے ہیں جو بتاتا ہے کہ معاشرہ کی تشکیل کے بنیادی اصول کیا ہیں.اسلام کا فلسفہ
دنیوی زندگی اور حیات اخروی دونوں پر محیط ہے.اس کے مطابق یہ دونوں زندگیاں
الگ الگ نہیں ہیں.دراصل زندگی ایک تسلسل کا نام ہے جو لمحہ بھر کے لئے موت کے
وقت ٹوٹ جاتا ہے.موت بھی در حقیقت ایک زندگی سے دوسری زندگی میں جانے کا
نام ہے.اس کے برعکس مادیت کے نزدیک زندگی شعور کا ایک عارضی اور مختصر عرصہ
ہے جو ہمیں اتفاقا مل گیا ہے.موت کے ساتھ ہی انسان کی ہستی، نیستی اور عدم کے
اندھیروں میں ڈوب جاتی ہے.پس اس فلسفہ کے مطابق سماجی نظام کا منتہائے نظر
صرف اور صرف اتنا ہے کہ اس مختصر عرصہ حیات کی ضرورت کو کسی نہ کسی طرح پورا کر
لیا جائے.فرد صرف اس وقت تک معاشرہ کے سامنے جوابدہ ہے جب تک وہ زندہ
ہے اور یہ جوابدہی بھی صرف ان جرائم تک محدود ہے جو دکھائی دیں اور جن کا سراغ
لگایا جا سکتا ہو.انسان کے مخفی خیالات، نیتیں، منصوبے سازشیں اور ایسے جرائم جو
عیاری اور چالاکی کے پردوں میں چھپ کر رہ جاتے ہیں احتساب سے بالا ہیں.74
Page 87
مزید برآں معاشرہ کے خلاف کئے جانے والے جرائم صرف اس صورت میں جرائم
قرار پاتے ہیں جب ارتکاب جرم کا یقینی ثبوت موجود ہو.پس انصاف کے تقاضے
پورے نہ ہونے کا احتمال بہر حال موجود رہتا ہے.ایسے سماجی نظام میں سطحی اور محدود
انصاف ہی ممکن ہے جو معاشرتی جرائم کی حوصلہ شکنی کرنے کی بجائے ان کی
حوصلہ افزائی کرتا ہے.اور یوں معاشرہ میں گروہی اور ذاتی مفادات کے حصول کی
ایک دوڑ شروع ہو جاتی ہے.ایک ملحد یا نیم ملحد معاشرہ میں جہاں موت کے بعد جزا سزا کے تصور کو کلیتہ رد کر
دیا گیا ہو یا یہ تصور اتنا مہم ہو کہ عملاً اس کا ہونا نہ ہونا برا بر ہو کر رہ جائے وہاں جرم کی
ٹھوس اخلاقی اصولوں پر مبنی تعریف تلاش کرنا بے حد مشکل کام ہے.پس ایسے معاشرہ
کے لوگ قانون شکنی کے بعد صحیح طور پر یہ سمجھ ہی نہیں سکتے کہ انہوں نے کسی جرم کا
ارتکاب کیا بھی ہے یا نہیں.آخر قانون ہے کیا ؟ کیا یہ کسی مطلق العنان انسان کے
منہ سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں؟ کیا کسی جابر حکومت کے احکام کو قانون کہا جائے؟ کیا
کثرت رائے سے کئے جانے والے فیصلے قانون کہلائے جانے کے مستحق ہونگے ؟
ایک عام انسان ان میں سے کس قانون
کو صیح اور اخلاقیات کے ٹھوس فلسفہ پر مبنی سمجھے
گا؟ بلکہ سوال تو یہ ہے کہ آخر کون سا اخلاقی فلسفہ؟ اگر انسان کسی بالا ہستی کا
مرہون منت نہ ہو حیات بعد الموت پر ایمان ہی نہ رکھتا ہو اور اخروی زندگی میں
اسے اپنے اعمال کی جوابدہی کا کوئی خوف نہ ہو تو ایسا شخص مذکورہ بالا مسائل کا جو بھی
حل تجویز کرے گا وہ ایک ذمہ دار معاشرہ کے تقاضوں سے ہم آہنگ نہیں ہوسکتا.اسے تو صرف یہ چند روزہ زندگی گزارنی ہے.معاشرہ اور معاشرتی نظام کی تو اسے
محض اپنے فائدہ کے لئے ضرورت ہے.اگر وہ معاشرہ میں کسی اتھارٹی کی اطاعت
کرتا ہے تو محض ضرورۃ ایسا کرتا ہے ورنہ اگر معاشرتی زندگی کو ترک کرنے میں اسے
75
Page 88
فائدہ نظر آئے اور معاشرتی نظام سے فرار اختیار کر کے وہ کچھ مزے لوٹ سکے اور
عیاری اور چالاکی سے اپنے جرائم پر پردہ ڈال سکے تو کونسی اخلاقی پابندی ہے جو اسکی
راہ میں حائل ہوسکتی ہے؟
ایسے معاشرہ جو خدا تعالیٰ کے تصور سے عاری ہیں اور مادہ پرستی جنکا شعار ہے ان
میں جرائم کا رجحان نفسیاتی طور پر بڑھنے لگتا ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسکی
جڑیں مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی جاتی ہیں.بعینہ یہی وہ نفسیاتی کیفیت ہے جسے
قرآن کریم نے ایک مادہ پرست معاشرہ کا لب لباب قرار دیا ہے.ہستی باری تعالیٰ
اور بعث بعد الموت کے منکرین کہتے ہیں کہ :
إِنْ هِيَ إِلا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَ مَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِين O
(سورۃ المومنون آیت ۳۸)
ترجمہ.ہماری تو صرف یہی دنیا کی زندگی ہے.ہم مرتے بھی ہیں اور
زندہ بھی رہتے ہیں اور ہم ہر گز اٹھائے نہیں جائیں گے.صرف یہی نہیں بلکہ کفار پہلے زمانوں میں مبعوث ہونے والے خدا کے
فرستادوں سے تمسخر کے رنگ میں پوچھتے ہیں.وَقَالُوا أَ إِذَا كُنَّا عِظَامًا وَّ رُفَاتاً أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا
(سورۃ بنی اسرائیل آیت ۵۰)
ترجمہ.اور وہ کہتے ہیں کہ جب ہم محض ہڈیاں رہ جائیں گے اور
ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہم ضرور ایک نئی تخلیق کی صورت میں
اٹھائے جائیں گے.قَالُوا أَ إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا ءَ إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ
(سورۃ المومنون آیت ۸۳)
ترجمہ.وہ کہتے تھے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو
76
Page 89
جائیں گے تو کیا ہم پھر بھی ضرور اٹھائے جائیں گے.قرآن کریم کے مطابق ایک مادہ پرست معاشرہ کی تمام برائیوں کی جڑ یہی عقیدہ
ہے اور یہی وجہ ہے کہ اخروی زندگی اور یوم حساب پر اس قدر زور دیا گیا ہے.بخاری کی ایک حدیث میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مستطیل بنائی اور اس کے وسط میں لمبائی کے رخ
ایک خط کھینچا جس کا بالائی سرا مستطیل سے باہر نکلا ہوا تھا پھر آپ نے اس خط کو قطع
کرتے ہوئے کئی چھوٹے افقی خطوط کھینچے اور اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ شکل
انسانی زندگی کو ظاہر کرتی ہے.مستطیل جس نے ان خطوط کو گھیرا ہوا ہے موت ہے.درمیانی خط انسان کی خواہشات کی عکاسی کرتا ہے اور چھوٹے خطوط زندگی میں آنے
والے ابتلاؤں اور مصائب کو ظاہر کرتے ہیں.آپ نے فرمایا کہ اگر وہ ان میں کسی
ایک مصیبت سے بچ نکلتا ہے تو دوسری کا شکار ہو جاتا ہے.ترمذی کی ایک حدیث
میں موت کو انسان کی آرزوؤں اور خواہشوں کا اختتام قرار دیا گیا ہے.مادہ پرست معاشرہ کی چار خصوصیات
مَاسَلَكَكُمْ فِي سَقَرَه قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ
الْمِسْكِيْنَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِفِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ
(سورۃ المدثر آیات ۴۳ تا ۴۷)
ترجمہ.تمہیں کس چیز نے جہنم میں داخل کیا.وہ کہیں گے ہم نمازیوں میں
سے نہیں تھے.اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے.اور ہم بھی لغو
باتیں کرنے والوں کے ساتھ لغو باتوں کے مرتکب ہوا کرتے تھے اور ہم
جزا سزا کے دن کا انکار کیا کرتے تھے.77
Page 90
لادین اور مادہ پرست معاشرہ کے خدو خال کو اس سے زیادہ معین اور
جامع الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے.ایسے معاشرہ کی خصوصیات یہ ہیں:
ا.اللہ تعالیٰ کی عبادت سے اعراض
۲.غرباء اور مساکین کو کھانا نہ کھلانا
۳.لغو اور بے مقصد مشاغل
۴.احتساب اور جزا سزا کے دن کا انکار
اس مضمون پر مزید روشنی ڈالنے سے پہلے ایک ایسی الجھن کا دور کرنا ضروری ہے
جس کی وجہ سے ایک بیمار معاشرہ کے مرض کی صحیح تشخیص مشکل ہو جاتی ہے.وہ
معاشرے جو خدا تعالیٰ اور یوم آخرت پر بظاہر پختہ ایمان رکھتے ہیں ان میں بھی
مذکورہ بالا برائیاں پھیل رہی ہیں اس لئے منطقی طور پر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ
اللہ تعالیٰ حیات بعد الموت اور جزا سزا کے دن پر ایمان رکھنے والے کیسے ان برائیوں
کا شکار ہو سکتے ہیں.پس سوال یہ ہے کہ ایسے معاشرے بھی مادہ پرستی میں کیوں
ڈوبے ہوئے ہیں؟ لیکن جب ہم ان لوگوں کے ایمان و اعتقاد کا بنظر غائر جائزہ لیتے
ہیں تو اس سوال کا جواب تلاش کرنا چنداں مشکل نہیں رہتا.حقیقت یہ ہے کہ
اللہ تعالیٰ کی ہستی پر محض ایک فلسفیانہ اور موہوم سا ایمان لوگوں کے معاشرتی رویوں
پر ہرگز اثر انداز نہیں ہوسکتا.اسکی وجہ یہ ہے کہ ایسے عقائد محض علمی نوعیت کے ہوتے
ہیں اور ایک ذمہ دار اور صالح کردار میں نہیں ڈھل سکتے.یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک
شخص اللہ تعالیٰ پر سچا اور حقیقی ایمان بھی رکھتا ہو اور کذب و افتراء خود غرضی، حق تلفی
بدعنوانی اور بے رحمی جیسے رزائل کا شکار بھی ہو.اگر ایسا ہو تو اس قسم کے معاشرہ میں
اللہ تعالیٰ کا تصور محض سطحی، خیالی اور غیر مؤثر ہو کر رہ جاتا ہے اور انسانی کردار کی
تشکیل میں کوئی فعال کردار ادا نہیں کر سکتا.حیات بعد الموت اور جزا سزا کے دن پر
78
Page 91
ان لوگوں کا ایمان بھی درحقیقت ایک واہمہ سا ہوتا ہے.اپنی پسند نا پسند کا سوال پیدا
ہونے پر اولیت اپنے ذاتی اور فوری مفاد ہی کو حاصل ہوتی ہے اور اسے ہی ترجیح دی
جاتی ہے.آنے والی زندگی کی ہرگز پرواہ نہیں کی جاتی.جب ہم کسی مادہ پرست معاشرہ کی بات کرتے ہیں تو صرف ایسا معاشرہ ہی نہیں
ہوتا جس نے ہستی باری تعالیٰ اور حیات آخرت کے تصور سے علی الاعلان بغاوت کی
ہو.ہستی باری تعالیٰ پر بظاہر ایمان رکھنے والے اور اس کا انکار کرنے والے اکثر
معاشروں میں اگرچہ نظریاتی اعتبار سے بظاہر بعد المشرقین دکھائی دیتا ہے مگر
بایں ہمہ عملاً ان دونوں کے مابین گہری مماثلت پائی جاتی ہے.اعمال کی جوابدہی کا تصوّر
ایک مادہ پرست معاشرہ کے تصور کے برعکس قرآن کریم انسان کے محاسبہ اور
مواخذہ کا تصور پیش کرتا ہے.فرمایا:
وہ وہ
ہ وہ وہ و
لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوتِ وَ مَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تَبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ
- و و
يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ ، فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلَّ
280
شَيْءٍ قَدِيرٌ
ط
(سورۃ البقرہ آیت ۲۸۵)
ترجمہ.اللہ ہی کا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے.اور خواہ
تم اُسے ظاہر کرو جو تمہارے دلوں میں ہے یا اُسے چھپاؤ اللہ اس کے
بارہ میں تمہارا محاسبہ کرے گا.پس جسے وہ چاہے گا بخش دے گا اور جسے
چاہے گا عذاب دے گا.اور اللہ ہر چیز پر جسے وہ چاہے دائمی قدرت
رکھتا ہے.قرآن کریم اس کے متعلق مزید فرماتا ہے.79
Page 92
وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ
عَنْهُ مَسْئُولًا
(سورہ بنی اسرائیل آیت ۳۷)
ترجمہ.اور وہ موقف اختیار نہ کر جس کا تجھے علم نہیں.یقیناً کان اور آنکھ
اور دل میں سے ہر ایک سے متعلق پوچھا جائے گا.اس آیت کریمہ میں دل سے مراد وہ قوت ہے جو تمام انسانی اعمال کے پیچھے
کارفرما ہے.قرآن کریم کے محاورہ میں فواد سے مراد فیصلہ کرنے والی وہ قوت
ارادی ہے جو دماغ سے ایسے ہی کام لیتی ہے جیسے کوئی کمپیوٹر کو چلاتا ہے.نیکی اور
بدی کا منبع و ماخذ یہی قوت ارادی ہے اور مرنے کے بعد بھی یہی قوت زندگی کی ایک
نئی شکل پا کر سماعت اور بصارت کے ساتھ اپنے اعمال کی جوابدہ ہوگی.آیئے اب ہم ایمان باللہ سے عاری معاشروں کی خصوصیات کا کچھ تفصیلی مطالعہ
کرتے ہیں.ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور حیات آخرت پر عدم ایمان کی مبہم سی کیفیت
مخفی رہتی ہے جس کا شعوری طور پر پورا احساس نہیں ہوتا.عقیدہ کی حد تک تو انسان
بظاہر اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے اور اخروی زندگی کو تسلیم کرتا ہے مگر عملی زندگی میں اس
ایمان کی کوئی جھلک نظر نہیں آتی.ہاں کبھی یہ ضرور ہوتا ہے کہ اگر انسان کسی بحران
سے دو چار ہو جائے تو لاشعور میں دبی ہوئی پوشیدہ حقیقتیں اس پر ظاہر ہو جاتی ہیں.بصورت دیگر کئی نسلیں گزر جاتی ہیں اور انسان کو اپنے عقائد کی کمزوری اور بے یقینی کا
احساس تک نہیں ہوتا اور جب رفتہ رفتہ ایک دور اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اور دنیا
بتدریج ایک نئے دور میں داخل ہونے لگتی ہے تو بحیثیت مجموعی معاشرہ میں ان عقائد کا
از سر نو جائزہ لینے کا رجحان پیدا ہو جاتا ہے جو اسے اپنے آباء و اجداد سے ورثہ میں
ملے ہوں.تب اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت کا انکار جواب تک لاشعور میں مخفی تھا ابھر کر
سامنے آنے لگتا ہے اور لذتوں کی ناجائز تلاش میں گم معاشرہ جب ہستی باری تعالیٰ
80
80
Page 93
اور حیات آخرت کا شعوری طور پر انکار کر دیتا ہے تو پھر انحطاط اور اعلیٰ اقدار کی پامالی
کا سفر بڑی سرعت کے ساتھ اپنے منتہی کو پہنچ جاتا ہے.تہذیب انسانی کا سفر ہمیشہ سے عدم شائستگی اور اجڈ پن سے شائستگی کی طرف ہوتا
چلا آیا ہے.تاریخ انسانی کے ہر دور اور ہر خطہ ارض میں یہی اصول کارفرما نظر آتا
ہے.انسانی کردار کے بنیادی اور جبلی محرکات اور تقاضے تبدیل نہیں ہوا کرتے البتہ
ان محرکات اور تقاضوں کی تکمیل اور تسکین کے طریق اور ذرائع بدلتے رہتے ہیں.مثلاً پیٹ تو گوشت یا سبزی کھا کر بھرا جا سکتا ہے مگر غذا کی اقسام اور معیار میں بڑا
فرق ہو سکتا ہے.سبزی اور گوشت تازہ بھی ہو سکتے ہیں اور باسی بھی.انہیں مختلف
طریقوں سے پکا کر اور اگر کوئی چاہے تو کچا بھی کھا سکتا ہے.معاشرتی ارتقاء کے
ساتھ ساتھ انسانی خواہشات کی تکمیل کے انداز بھی بدلتے رہتے ہیں اور پہلے سے
زیادہ شائستہ لطیف اور پر تکلف ہوتے چلے جاتے ہیں.ترقی کے اس جاری عمل کی
رفتار کا دارو مدار بڑی حد تک لوگوں کے معاشی حالات اور سیاسی عوامل پر ہوا کرتا
ہے.تا ہم معاشرہ کے اعلیٰ طبقات ہر اول دستے کے طور پر ہمیشہ آگے سے آگے
بڑھتے چلے جاتے ہیں.اگر چہ ان کے سفر کی رفتار گھٹتی بڑھتی رہتی ہے تا ہم جب اس
تہذیبی ارتقاء کا سفر بلوغت اور کمال کو پہنچتا ہے تو حد سے بڑھا ہوا تکلف اور تصنع
اور بعض دیگر منفی عوامل ترقی کے اس رجحان کا رخ تنزیل کی جانب پھیر دیتے ہیں.نتیجه زوال پذیر معاشروں کی تہذیبی گنگا لطافت سے کثافت کی طرف الٹی بہنی شروع
ہو جاتی ہے اور اس کا رخ اعلیٰ سے ادنی کی طرف مڑ جاتا ہے.یہ ایک بہت وسیع
مضمون ہے اور تفصیلی مطالعہ کا متقاضی ہے.مجھے افسوس ہے کہ آج کے خطاب میں
اتنی تفصیل کی گنجائش نہیں ہے.تاہم میں چند نکات کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا
ہوں.81
Page 94
جب ایک معاشرہ بیمار ہو جاتا ہے یا بے جا تکلفات کے باعث عدم توازن کا
شکار ہو جاتا ہے تو وہ تیزی سے زوال پذیر ہونا شروع ہو جاتا ہے اور لوگ پہلے کی
طرح جانوروں کی مانند اندھا دھند اپنی سفلی خواہشات کی تسکین کے سامان ڈھونڈ نے
لگتے ہیں.ضروری نہیں کہ یہ صورت حال ہر قسم کی سماجی اور ثقافتی سرگرمیوں میں
دکھائی دے لیکن اس کی جھلک ان انسانی تعلقات اور رویوں میں واضح طور پر دکھائی
دینے لگتی ہے جو لذات کے گرد گھومتے ہیں.بنی نوع انسان کے جنسی تعلقات کے
حوالہ سے دیکھا جائے تو یہ نکتہ خوب واضح ہو جاتا ہے کہ جنسی جذبہ ایک بنیادی جبلت
ہے.قدرت نے تمام عالم حیوانات میں بقائے نسل کی خاطر اس جبلت میں ایک
لذت بھی رکھ دی ہے لیکن انسانوں اور جانوروں میں فرق یہ ہے کہ انسان فطری
خواہشات کو جانوروں کی طرح پورا کرنے کی بجائے رفتہ رفتہ اپنے جذبوں کی تسکین
کیلئے شائستہ اور مہذب انداز اختیار کر لیتا ہے.یادر ہے کہ ان جذبات کی تسکین ہی
قدرت کا مقصود نہیں بلکہ اصل مقصد بقائے نوع انسانی ہے.لذات کا حصول محض
ثانوی حیثیت رکھتا ہے لیکن ایک بیمار معاشرہ میں جنسی جذبوں کی تسکین فی ذاتہ مقصود
بن جاتی ہے اور نسل انسانی کی بقا کا مقصد ثانوی حیثیت اختیار کر لیتا ہے.شادی بیاہ اور اس سے وابستہ جنسی تعلقات پر عائد پابندیاں (Taboos) ایک
ماہر عمرانیات کے نزدیک تو معاشرہ کے ارتقائی عمل کا نتیجہ ہیں.ممکن ہے کہ اس کے
نزد یک مذہب کا اس عمل سے براہ راست کوئی تعلق نہ ہولیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ
تدریجی عمل کسی بالا ہستی کے ارادہ کا نتیجہ ہے یا اتفاقات کے سہارے خود بخود آگے
بڑھتا رہا ہے؟ اس کا جواب خواہ کچھ بھی ہو اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ
بنیادی فطری خواہشات کی تسکین کے طریق رفتہ رفتہ پہلے سے زیادہ شائستہ اور
مہذب ہوتے چلے گئے ہیں.88
82
Page 95
بے محابا جنسی میل جول اور اختلاط بھی اسی مرض کی علامت ہے اور یہ سلسلہ ان
تعلقات کی آزادی تک محدود نہیں رہتا بلکہ اس کے ساتھ کئی اور عوامل بھی شامل
ہو جاتے ہیں جو انسانی زندگی کے اس نہایت اہم حصہ کے ماحول کو مکدر کر دیتے
ہیں.یہاں تک کہ جنسی تعلقات کے جائز یا نا جائز ہونے کی بحث کو ماضی کا قصہ سمجھ کر
حقارت سے نظر انداز کر دیا جاتا ہے.بے شک بعض کٹر مذہبی حلقوں میں یہ موضوع
پھر بھی زیر بحث رہتا ہے لیکن ٹی وی اور اخبارات وغیرہ میں ایسے مباحث کو دیکھیں تو
صاف نظر آتا ہے کہ پرانے طرز کے کٹر مذہبی لوگوں کی تعداد گھٹ رہی ہے اور ان کی
اہمیت بھی کم ہوتی جا رہی ہے.مغرب میں تو یہ خیال فیشن کی طرح زور پکڑ رہا ہے کہ
جنس ایک فطری جذبہ ہے جس کی بلا جھجک اور بلا روک ٹوک تسکین ہونی چاہئے.اس
موضوع پر بات کرتے وقت طبقہ نسواں کی مخصوص شرم و حیا قصہ پارینہ بنتی جا رہی
ہے.عریانیت، برہنگی، بے حجابی ، جسم کو چھپانے کی بجائے اس کی نمائش، بے باک
گفتگو اور گناہ کے فخریہ اعلان کو سچائی کا بر ملا اظہار تصور کیا جاتا ہے.اگر فطری تقاضوں کے نام پر جنسی خواہشات کی بلا روک ٹوک تسکین ضروری ہے
تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اس دلیل کے ماتحت دیگر طبعی تقاضے کیوں پورے نہیں
کئے جاتے ؟ کیا ہر پسندیدہ چیز کے حصول کی طبعی خواہش حیوانوں اور انسانوں میں
یکساں طور پر نہیں پائی جاتی؟ کیا مشتعل ہو کر جذبات کا وحشیانہ اظہار ایک طبعی حیوانی
تقاضا نہیں ہے؟ ایک کمزور کتا بھی ویسے ہی اپنی خواہشات کے ہاتھوں مجبور ہوتا ہے
جیسے ایک طاقتور کتا.فرق صرف اتنا ہے کہ طاقتور کتا کاٹ کھاتا ہے اور کمزور صرف
بھونکنے پر ہی اکتفا کرتا ہے.پھر کیا انسان کیلئے بھی جائز ہوگا کہ وہ بھی اپنے فطری
تقاضوں کا اسی طرح بلا روک ٹوک اظہار کرے؟ آخر معاشرہ میں بعض باتیں عام
طور پر کیوں ممنوع سمجھی جاتی ہیں ؟ تہذیب اور اخلاق کے ضوابط کیا ہیں؟ شائستگی کے
888
83
Page 96
تصور کی کیا حقیقت ہے؟ یہ سب اوامر ونواہی کی پابندیاں ہی تو ہیں جو طبعی جذبات
اور خواہشات کے بلا روک ٹوک اظہار کے رستہ میں حائل ہو جاتی ہیں.اس لئے
سوال پیدا ہوتا ہے کہ صرف جنسی خواہشات ہی کے بے محل اور بے موقع ، خلاف
تہذیب و روایت، ناشائستہ اور ناجائز اظہار کی اجازت کیوں دی جائے؟
آج جو منظر ہمارے سامنے ہے اور جس صورت حال سے ہم دوچار ہیں اس کا
بغور جائزہ لینا اور صحیح تجزیہ کرنا بہت ضروری ہو گیا ہے.وہ سوچ جسے بزعم خود
جنسی آزادی کا نام دیا جاتا ہے وہ جنسی بے راہ روی تک ہی محدود نہیں رہتی بلکہ اس
کے شعلے زندگی کے دوسرے شعبوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا کرتے ہیں.چنانچہ ہم
دیکھ رہے ہیں کہ چوری چکاری اور لوٹ کھسوٹ کا رجحان کس قدر بڑھ رہا ہے اور
دوسروں کو اذیت اور دکھ پہنچا کر لوگ کتنی خوشی محسوس کرنے لگے ہیں.لوگوں کے
ذوق ہی بگڑ چکے ہیں.ہر جائز اور ناجائز حربہ سے لذت کے حصول کی ایک اندھی
دوڑ جاری ہے.ان گھٹیا اور سفلی رجحانات کے ہاتھوں اعلیٰ تہذیبی قدروں کے
خد و خال مسخ ہو رہے ہیں اور ارفع روایات پامال ہو رہی ہیں.اور زندگی پھر اس
وحشیانہ حالت کی طرف لوٹ رہی ہے جہاں سے سفر کا آغاز ہوا تھا.شادی بیاہ کے موقعوں پر طرح طرح کے رسم و رواج اور افراد پر عائد کردہ سماجی
پابندیاں ہی نہیں عشق و محبت کے معاملات، رومانی سلسلے اور معاشقے سبھی اس بنیادی
فطری جذبہ کے مختلف مظاہر ہیں.شعر و ادب، آرٹ، موسیقی، فیشن، فنون سے متعلق
نمائشیں، خوشبو سے پیار، شائستگی، وضع داری اور دیگر تہذیبی رویے اگر تمام تر نہیں تو
کسی حد تک اسی بنیادی جذبہ کا سماجی اظہار ہی تو ہیں.معاشرہ نے ہزاروں سال کے ارتقائی عمل سے گزر کر یہ تہذیبی اقدار ورثہ میں
پائی ہیں.خدشہ یہ ہے کہ مستقبل کی نسلیں ان کے خلاف علم بغاوت لیکر نہ اٹھ کھڑی
84
Page 97
اور دیکھنے والی آنکھ کو صاف دکھائی دے رہا ہے کہ نئی نسل اس رستہ پر چل نکلی
ہے.تہذیب اور روایت سے بغاوت کے نتیجہ میں ممکن ہے کہ ہر چیز کلیتہ تو مسترد نہ
کی جا سکے اس سمت میں سفر شروع ہو چکا ہے.معاشرہ سے آزاد اور بے پرواہ
زندگی اذیت رسانی میں لذت محسوس کرنا ، یہی ازم، جنسی تشدد اور حیوانات کی مانند
جنسی خواہشات کی تکمیل کا جنون چند ایک ایسی مثالیں ہیں جو مذکورہ بالا رجحانات کا
پستہ دے رہی ہیں.جو شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ نئی نسل کس سمت میں دوڑی چلی جا رہی ہے اسے جی
کڑا کر کے ان باغی پراگندہ حال میلے کچیلے لڑکے لڑکیوں کو جا کر دیکھنے کی ہمت کرنی
چاہئے جو ریوڑوں اور گروہوں کی شکل میں اکٹھے رہتے ہیں.وہاں جا کر معلوم ہوتا
ہے کہ اب نفاست اور خوشبو کی جگہ غلاظت اور عفونت لے چکی ہے.بے داغ اور
صاف ستھرے لباس کی بجائے اب پھٹے پرانے بوسیدہ چیتھڑے فیشن کا نشان بن گئے
ہیں.وہ دن گئے جب لباس پر ایک معمولی سا داغ بھی بے حد خفت کا باعث ہوا
کرتا تھا.اب تو پھٹی پرانی جینز (Jeans) بلکہ جسم کے بعض حصوں کی ایک جھلک
دکھانے کے لئے خاص طور پر پھاڑی گئی پتلونیں ایک نئی پتلون سے کہیں زیادہ قیمتی
سمجھی جاتی ہیں.یہ صحیح ہے کہ ماضی کے روایتی ورثہ سے بے زاری کی یہ انتہائی
علامات سارے معاشرہ میں دکھائی نہیں دیتیں لیکن بیماری کا آغاز ہو تو ضروری نہیں
کہ سارا بدن فوراً ہی اس سے متاثر ہو جائے تا ہم جسم پر کہیں کہیں ظاہر ہونے والے
ناسور بیمار کی حالت کا پتہ ضرور دیا کرتے ہیں.جب ایک معاشرہ بیمار ہونے لگتا ہے
تو غیر ذمہ دارانہ رویے بھی سر اٹھانے لگتے ہیں.نظم وضبط کا فقدان اور فساد کا دور
دورہ ہو جاتا ہے اور مختلف شعبہ ہائے زندگی میں انحطاط اور زوال کے آثار ظاہر
ہونے لگتے ہیں.85
Page 98
لذت کی ایسی تلاش جلد ہی تبدیلی اور تنوع کا تقاضا کیا کرتی ہے تاکہ پہلے سے
بڑھ کر لطف اٹھایا جا سکے.اگر ایسا نہ ہو تو جو چیزیں پہلے لذت دیتی تھیں بے مزہ
ہونے لگتی ہیں.تمباکو نوشی اور دیگر روایتی نشے اتنی تسکین دینے میں ناکام ہو جاتے
ہیں جس قدر ایک بے چین اور بے سکون معاشرہ تقاضا کرتا ہے.پس ہر قسم کی
منشیات اور نشہ کے اس خطرناک رجحان کی روک تھام کیلئے جو بھی اقدامات کئے
جائیں وہ نا کافی ثابت ہوتے ہیں.نشہ کرنے والوں کو تیز سے تیز نشے کی تلاش رہتی
ہے.نتیجہ جلد ہی Crack جیسی خوفناک قسم کی زہریلی اور جان لیوا منشیات
ایجاد کر لی جاتی ہیں.موسیقی کی دنیا میں بھی اس صدی کی آخری دہائیوں میں رفتہ رفتہ ایسے ہی
رجحانات پیدا ہو گئے ہیں.موسیقی میں گزشتہ چند صدیوں میں ہونے والی ترقی کا
موازنہ اگر موجودہ صدی کی آخری چند دہائیوں میں سامنے آنے والی تیز دھما کہ خیز
اور کان پھاڑنے والی موسیقی سے کیا جائے تو بہت سے دلچسپ اور حیران کن حقائق
سامنے آئیں گے.ذاتی طور پر موسیقی کے متعلق مجھے کچھ زیادہ علم نہیں ہے اس لئے
اس پر میرا تبصرہ اگر کچھ عجیب نظر آئے اور حقائق کچھ اور ہوں تو میں اس کے لئے
معذرت خواہ ہوں تاہم میرا وجدان مجھے بتاتا ہے کہ گزشتہ چند صدیوں میں مغرب
میں موسیقی کی جو تدریجی ترقی ہوئی وہ اعلیٰ ذوق اور شاندار نغمگی کی آئینہ دار تھی.یہ
موسیقی دل اور دماغ دونوں کیلئے بیک وقت سکون بخش محسوس ہوتی تھی.بہترین
موسیقی تو وہی ہے جو قلب و ذہن کی باطنی نغمگی سے ہم آہنگ ہو کر روح کی
گہرائیوں میں اتر جائے.موسیقی کے ارتقاء کا آخری مقصد ہم آہنگی اور امن وسکون
کی تلاش ہی تو ہے.عظیم موسیقاروں نے یقیناً ایسی دھنیں بھی ترتیب دیں کہ جو
آتش فشاں پہاڑوں کے پھٹنے، طوفانوں، بادلوں کی گرج اور بجلی کی کڑک اور
98
86
Page 99
شور و غوغا اور ہلچل کا سا تاثر پیدا کرتی تھیں.دراصل ایسی موسیقی مظاہر فطرت کے
ساتھ ایک گونہ مطابقت رکھتی تھی اور اس کی یادوں کے انمٹ نقوش خود زندگی کے
حافظہ پر مرتسم تھے اور کبھی کبھی یہ موسیقی جب اپنے نقطہ عروج کو پہنچتی تو یوں لگتا جیسے
اس کے اونچے سروں سے یہ کائنات پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی مگر اس کے
با وجود سامعین یوں دم سادھے بے حس و حرکت بت بنے بیٹھے رہتے جیسے
صوت و آہنگ کے اس بے پناہ سیلاب میں بہے چلے جا رہے ہیں.ایک گہری
خاموشی اور سناٹے کا عالم طاری ہو جاتا.حرکت تو کجا آنکھ تک جھپکنے کی فرصت نہ ملتی
اور جب موسیقی اپنے اختتام کو پہنچتی تو سارا ہال تالیوں کے بے پناہ شور میں ڈوب
جاتا لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ایسی موسیقی کتنی ہی تند و تیز ، جذباتی اور ہیجان انگیز
کیوں نہ ہو سامعین کو تشدد، توڑ پھوڑ اور بغاوت پر آمادہ نہیں کیا کرتی تھی.اس کا
پیغام تو بہت ہی ارفع اور اعلیٰ تھا یعنی امن ، سکون اور شانتی جس سے انسان کے
لطیف اور ارفع احساسات بیدار ہوں اور سطحی کثافتیں دھل جائیں.مگر افسوس ہے کہ گزشتہ چند دہائیوں میں یہ منظر بالکل بدل چکا ہے.نئی نسل کے
کان ایسی موسیقی کے شور سے پھٹ رہے ہیں جو انسان کے اندر کی حیوانیت کو انگیخت
کرتی ہے اور اسے تہذیب کی بجائے وحشت کی طرف لے جاتی ہے.یہ بے قرار
اور بے چین نسل صرف وہی موسیقی سننے کی خواہش مند ہے جو اس کے جنون اور بے
چینی کی آگ کو اور بھی بھڑ کا دے.موسیقی جس قدر ہیجان انگیز اور ہنگامہ خیز ہو اسی
قدر پسند کی جاتی ہے.میں ایک بار پھر اپنے کسی ایسے تبصرہ پر معذرت خواہ ہوں جو
پاپ اور کلاسیکل موسیقی سے میری ناواقفیت پر مبنی ہو.تا ہم ایک بات میں پورے
وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ہنگامہ خیزی، دیوانگی، بغاوت اور وحشت کے رجحانات
انسان کی ارفع و اعلیٰ استعدادوں کو تیزی کے ساتھ برباد کر رہے ہیں.87
Page 100
پروفیسر بلوم (Bloom) نے جو مغربی موسیقی سے بخوبی واقف ہیں، ایک کتاب
"The Closing of the American Minds" کے عنوان سے لکھی ہے.موسیقی کے بارہ میں ان کے اور میرے خیالات میں بہت مماثلت پائی جاتی ہے.وہ
بھی نوحہ کناں ہیں کہ آج کے نوجوانوں میں اعلیٰ ذوق اور لطیف احساسات بتدریج
مفقود ہوتے جا رہے ہیں.وہ کہتے ہیں کہ آج کے نوجوان راک میوزک Rock)
(Music کوسن سن کر وحشی بن چکے ہیں.ان کے نزدیک موسیقی اگر روح کی غذا
ہے تو راک میوزک روح کیلئے ایک مضر غذا ہے.بہت سی واضح اور کھلی علامات ایسی ہیں جو معاشرہ کی اس بیمار حالت کا پتہ دیتی
ہیں.زندگی کا سکون لٹ رہا ہے.انسان صبر وسکون اطمینان قلب امن اور تحفظ کے
احساس سے عاری ہو چکا ہے.وہ ہستی باری تعالیٰ کا انکار تو کر سکتا ہے مگر ان طاقتور
قوانین قدرت کا انکار اس کے بس کی بات نہیں جو اپنی خلاف ورزی کرنے والوں کو
سزا دینا خوب جانتے ہیں.تمام مادہ پرست معاشروں میں برائی کے بڑھنے اور
پھیلنے کے اسباب کم و بیش ایک سے ہوتے ہیں.اس موضوع پر کسی قدر بحث پہلے کی
جا چکی ہے یہاں بطور یاد دہانی مختصراً ان اسباب کا اعادہ کیا جاتا ہے.(۱) دہریت کا بڑھتا ہوا رجحان
(ب) اس قادر مطلق خدا پر ایمان کی کمزوری جو انسانی معاملات پر پوری نظر
رکھتا ہے اور ہر آن دیکھ رہا ہے کہ انسان اپنے اعمال اور کردار کی تشکیل کس نہج پر
کرتا ہے.(ج) معاشرہ کی روایتی اور اخلاقی اقدار کا رفتہ رفتہ کمزور پڑ جانا.(د) زندگی کے حقیقی مقاصد کو فراموش کرنے کا بڑھتا ہوا رجحان اور حصول مقصد
کے ذرائع کو ہی مقصود بالذات سمجھ لینا.88
Page 101
یہ ہے وہ صورتحال جو آج کے مہذب اور ترقی یافتہ کہلانے والے معاشروں میں
ہمیں بالعموم نظر آتی ہے.اخلاقی اقدار کے کمزور پڑنے سے رفتہ رفتہ قانون سازی
اور حکومتی انتظامات بھی متاثر ہونے لگتے ہیں.جب معاشرہ میں نہ تو کسی الہی قانون
کو قبول کیا جائے اور نہ ہی دائمی اخلاقی قدروں اور ارفع روایات کو تسلیم کیا جائے
اور ان کی خلاف ورزی زندگی کا معمول بن جائے تو پھر اخلاق کے قائم کرنے کیلئے
کی جانے والی قانون سازی میں بھی نرمی اور لچک پیدا ہو جاتی ہے اور یوں اخلاق
کی عمارت کی بنیاد ہی متزلزل ہو جاتی ہے.گزشتہ چند صدیوں میں اس سلسلہ میں کی
جانے والی قانون سازی کا تقابلی جائزہ لیا جائے تو حقیقت خوب کھل کر سامنے آجاتی
ہے.کبھی آسکر وائلڈ کا وہ زمانہ بھی تھا جب ہم جنس پرستی کو ایک انتہائی سخت قابل سزا
جرم سمجھا جاتا تھا.وہ دن بیت گئے جب عفت اور پاکیزگی کو صرف ایک نیکی ہی نہیں
بلکہ سماجی عزت و وقار اور اعتماد کی علامت سمجھا جاتا تھا اور عصمت پر حرف آنے پر سختی
سے محاسبہ کیا جاتا تھا.اب تو یہ حالت ہے کہ جُرم کو مُجرم ہی نہیں سمجھا جاتا اور نہ ہی
اس کے ارتکاب پر خطرہ کے الارم بجنے لگتے ہیں.درحقیقت اصل مسئلہ یہی ہے کہ
جرم کی تعریف ہی سرے سے بدل رہی ہے.جس فعل کو کل تک جرم قرار دیا جاتا تھا
آج اسے جرم ہی نہیں سمجھا جاتا.کل تک جو جرم شرم و حیا اور سرزنش کے خوف سے
چھپ کر کیا جاتا تھا آج نہ صرف سب کے سامنے کھلے بندوں علانیہ ہو رہا ہے بلکہ
اس پر فخر کیا جاتا ہے.پس اگر یہ فلسفہ درست ہے اور زندہ رکھے جانے کے قابل
ہے تو ماننا پڑے گا کہ مذہبی اور اخلاقی فلسفے بالکل فرسودہ اور بے کار ہو چکے ہیں اور
آج کے دور میں ان کا کوئی مقصد باقی نہیں رہا.جرم کی سزا اور نیکی کی جزا کا آفاقی اصول ذی روح اور غیر ذی روح دونوں
کیلئے ایک مشترک قوت محرکہ کی حیثیت رکھتا ہے.بے جان اشیاء میں یہ اصول
89
Page 102
قوانین فطرت کے غیر شعوری عمل میں کارفرما نظر آتا ہے.زندہ اجسام میں
بی تخلیق
انسانی سے پہلے کے ارتقائی عمل کو اسی اصول نے آگے بڑھایا ہے جو نیم شعوری یا
نیم فعال حالت میں جاری رہا ہے.ارتقائی عمل کو بالکل نچلی سطح سے لیکر انسان کی سطح
تک دیکھا جائے تو یہ ادنی شعور سے اعلیٰ شعور کی جانب ایک سفر دکھائی دیتا ہے.ارتقائی سائنس کی اصطلاحات میں بات کی جائے تو جرم اور سزا اور نیکی اور جزا کے
اصول کو بقائے اصلح (Survival of the fittest) کا نام بھی دیا جا سکتا
ہے.ارتقاء کے سارے عمل میں یہی وہ قوت محرکہ ہے جس نے مسلسل اس سفر کو آگے
بڑھایا ہے.یہ بالکل نا قابل فہم بات ہے کہ ارتقاء کا یہ سفر جب انسان یعنی تخلیق کی اعلیٰ ترین
شکل میں اپنی تکمیل کو پہنچا اور شعور کی سطح تصور کی ہر چھلانگ سے بھی بلند تر ہوگئی تو
اچانک جرم وسزا کا سابقہ اصول بے کار اور معطل ہو کر رہ گیا.اگر تخلیق کا کوئی بلند
مقصد ہے تو پھر احتساب کی بھی کوئی شکل ضرور ہونی چاہئے ورنہ یہ سارا کاروبار عبث
اور بے معنی ٹھہرے گا.یہ انتہائی حیران کن امر ہے کہ بعض اوقات عظیم ترین دانشور
بھی ایسی واضح اور بولتی ہوئی صداقت کو سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں.نظریہ اضافت کو پیش کرنے والے عظیم سائنس دان البرٹ آئن سٹائن کا معاملہ
بھی کچھ ایسا ہی ہے.وہ کہتے ہیں.میں ایک ایسے خدا کا تصور نہیں کر سکتا جو اپنی ہی مخلوق کو جزاء یا سزا دیتا
ہے.ایک ایسا خدا جس کے اغراض و مقاصد ہم انسانوں کے اغراض و
مقاصد کی طرح ہوں.(جن کی تکمیل کیلئے اس نے جزاء سزا کا نظام
جاری کیا ہو ) مختصر یہ کہ میں ایک ایسے خدا کو تسلیم نہیں کر سکتا جو انسانی
کمزوریوں کا عکس اپنے اندر لئے ہوئے ہو.(البرٹ آئن سٹائن)
90
90
Page 103
اگر ایک خالق خدا موجود ہے (جس کا انکار البرٹ آئن سٹائن بھی نہیں کر سکے )
اور اگر کائنات میں جاری و ساری تمام سائنسی قوانین کو بنانے اور چلانے والا بھی
وہی خالق اکبر ہے تو پھر یہ بات بالکل نا قابل فہم ہے کہ وہ تخلیق کائنات کے آخری
مقصود یعنی انسان کو جرم و سزا کے قانون سے آزاد کر کے یونہی فساد اور ابتری میں
بے مقصد بھٹکنے کیلئے چھوڑ دے اور اس کے اعمال کا کوئی محاسبہ نہ ہو.آئن سٹائن کے
اس خیال سے صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ مخلوق کے تدریجی ارتقاء میں قانون جرم وسزا
کے کردار کو سمجھنے میں ناکام رہا ہے.نیز اس نے انسان کے اللہ تعالیٰ کی شبیہ پر پیدا
کئے جانے کے معنی بھی بالکل غلط سمجھے ہیں.انسان کو جو اللہ تعالیٰ کی شبیہ پر بنایا گیا ہے اس کے یہ معنی ہرگز نہیں ہیں کہ انسان
زمین پر خدا کا ایک کامل نمونہ ہے.اگر ایسا ہوتا تو پھر یہ زمین جنت تو کیا اس سے
بھی بڑھ جاتی.اس کا دوسرا نتیجہ یہ نکلتا کہ سب انسان ایک جیسے ہوتے بالکل ایک
دوسرے کے مشابہ.اس صورت میں یہ امر یقینا قابل غور ہے کہ پھر کیا ایسی جگہ
جنت کہلانے کے قابل ہوتی یا یکسانیت اور بوریت کا شکار ہو جاتی جہاں نہ رنگوں
میں کوئی تنوع ہوتا ، نہ قسم قسم کی خوشبوئیں ہوتیں.دراصل انسان کے خدا کی شکل پر
پیدا کئے جانے کا نہ تو یہ مقصد ہے اور نہ اس کے یہ معنی ہیں.گہری حکمت پر مبنی یہ
قول انسان کی ان استعدادوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے جو اسے عطا کی گئی ہیں.لہذا انسان کو ایک اعلیٰ مقصد کے حصول کے لئے مسلسل کوشاں رہنا چاہئے اور وہ اعلیٰ
مقصد یہ ہے کہ جہاں تک انسان کیلئے ممکن ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کو اپنا کر اپنی ذات
کی تعمیل کرے یہاں تک کہ اس کا وجود خدا نما وجود بن جائے.ان معنوں کے لحاظ
سے یہ کوئی ایسا معین اور محدود مقصد نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شبیہ اختیار کر کے انسان
اپنی شان و شوکت کو ساتھ لئے ایک جگہ بیٹھا رہے.چونکہ اللہ تعالیٰ کی ہستی اور اسکی
91
Page 104
صفات لامحدود ہیں اس لئے الوہیت کی جانب اختیار کیا جانے والا جو سفر بھی ہوگا
لا محمد ود ہوگا.اس راہ میں کامل ہو جانے کا مطلب صرف یہ ہے کہ انسان ایک ادنیٰ
حالت سے اعلیٰ حالت کی طرف مسلسل بڑھتا چلا جائے.اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات میں اکمل ترین ہے.وہ سب سے بڑھ کر
انصاف کرنے والا ہے.سب سے زیادہ مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے.ہر
چیز پر اس کی نگاہ ہے اور ہر شے کو وہ جاننے والا ہے.وہ سب کا خالق سب کا آقا
اور جزا سزا کے دن کا مالک ہے.سب تعریفیں اللہ ہی کیلئے ہیں.قرآن کریم
اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے.هُوَ اللهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ 0
هوده
ޅ
و
هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ
الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ هُوَاللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِيُّ
و
طوس و
المصور لَهُ الْأَسْمَاء الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَهُوَ
(سورۃ الحشر آیات ۲۳ تا ۲۵)
العزيز الحكيم
ترجمہ.وہی اللہ ہے جس کے سوا اور کوئی معبود نہیں.غیب کا جاننے والا
ہے اور حاضر کا بھی.وہی ہے جو بن مانگے دینے والا، بے انتہا رحم
کرنے والا (اور) بار بار رحم کرنے والا ہے.وہی اللہ ہے جس کے سوا
اور کوئی معبود نہیں.وہ بادشاہ ہے، پاک ہے، سلام ہے، امن دینے والا
ہے، نگہبان ہے، کامل غلبہ والا ہے، ٹوٹے کام بنانے ولا ہے (اور )
کبریائی والا ہے ، پاک ہے اللہ اُس سے جو وہ شرک کرتے ہیں.وہی
اللہ ہے جو پیدا کرنے ولا، پیدائش کا آغاز کرنے والا اور مصور ہے.تمام خوبصورت نام اسی کے ہیں.اس کی تسبیح کر رہا ہے جو آسمانوں اور
زمین میں ہے.اور وہ کامل غلبہ والا (اور ) صاحب حکمت.ہے.92
Page 105
یہ وہ خدا ہے جس نے زمین و آسمان پیدا کئے ہیں.اس کی ذات بشری
کمزوریوں سے بالکل پاک ہے.قرآن کریم بار بار ایمان لانے والوں
کو اللہ تعالیٰ
کے نشانات پر غور کرنے کی تاکید کرتا ہے.مثال کے طور پر فرماتا ہے.つ
تَبْرَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ
وَالحَيُوةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ
"
91 - 0
سموتِ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفُوتِ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى
280
مِن فُطُورِ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِنًا وَهُوَ حَسِيرٌ
( سورۃ الملک آیات ۲ تا ۵)
ترجمہ.بس ایک وہی برکت والا ثابت ہوا جس کے قبضہ قدرت میں
تمام بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر جسے وہ چاہے دائمی قدرت رکھتا ہے.وہی جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تا کہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں
سے کون عمل کے اعتبار سے بہترین ہے.اور وہ کامل غلبہ والا (اور )
بہت بخشنے والا ہے.وہی جس نے سات آسمانوں کو طبقہ در طبقہ پیدا کیا.تو رحمان کی تخلیق میں کوئی تضاد نہیں دیکھتا.پس نظر دوڑا.کیا تو کوئی رخنہ
دیکھ سکتا ہے؟ نظر پھر دوسری مرتبہ دوڑا، تیری طرف نظر ناکام لوٹ آئے
گی اور وہ تھکی ہاری ہوگی.اللہ تعالیٰ کی شبیہ کا صحیح مفہوم سمجھ لینے کے بعد جب انسان آغاز تخلیق سے لیکر
کائنات کے آج تک ہونے والے ارتقاء کو دیکھتا ہے تو پکار اٹھتا ہے کہ عدم شعور سے
شعور تک کا یہ سارا سفر اللہ تعالیٰ کی شبیہ اختیار کرنے اور انسانی وجود کو خدائی صفات
سے متصف کرنے کی کوشش ہی سے عبارت ہے.93
Page 106
اسلامی معاشرہ کا مخصوص ماحول
اسلام جس معاشرتی ماحول کو پیدا کرنا چاہتا ہے وہ مادہ پرستی کے مذکورہ بالا
ماحول سے اتنا ہی مختلف ہے جتنا بہار کا موسم خزاں سے مختلف ہوتا ہے.اسلام
معاشرہ کا جو تصور پیش کرتا ہے اس میں انسان کی فطری خواہشات میں ایک اعتدال
اور نظم و ضبط رکھا گیا ہے.حد سے بڑھی ہوئی خواہشات کی روک تھام کی گئی ہے.وجہ یہ ہے کہ اگر ان فطری خواہشات کو بے لگام چھوڑ دیا جائے تو انسانی جذبات اور
خواہشات کا پورا نظام درہم برہم ہو کر رہ جاتا ہے.اسلام خواہشات کی ایسی تکمیل کی
حوصلہ شکنی کرتا ہے یا اسے ممنوع قرار دیتا ہے جس کا آخری نتیجہ یہ ہو کہ معاشرہ
خوشیوں اور مسرتوں کی بجائے دکھوں سے بھر جائے.اس کے ساتھ ساتھ اسلام نئے
ذوق اجاگر کرتا ہے اور ایسے کاموں سے لذت و اطمینان حاصل کرنے کی صلاحیت کو
بڑھاتا ہے جو ممکن ہے کہ ایک غیر مہذب اور غیر تربیت یافتہ انسان کو بے کیف اور
بے لذت دکھائی دیں.پس اسلام انسانی ذوق کو اعلیٰ سانچوں میں ڈھالتا ہے.حیوانی خواہشات اور شہوات کی تربیت اور ان کی تہذیب و تعدیل کرتا ہے اور ادنیٰ
خواہشوں کو اعلیٰ اور ارفع خواہشات میں بدل دیتا ہے.سوال یہ ہے کہ یہ فیصلہ کیسے کیا جائے کہ موجودہ معاشرتی رجحانات معاشرہ کے
لئے کس حد تک نقصان دہ ہیں.میرے نزدیک اس سوال کا جواب بہت سادہ اور
آسان ہے.انسان کی صحت کی علامات کی طرح معاشرہ کی صحت کا اندازہ لگانے
کے لئے بھی کچھ علامات ہوتی ہیں.جب کوئی شخص کسی درد کے باعث بے چینی
اور کرب میں مبتلا ہو اور اسے کسی پہلو قرار نہ آئے تو اسے بیمار قرار دینے کے لئے کسی
ماہر طبیب یا بہت عقلمند انسان کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ ہر کوئی ان علامات کو دیکھ کر
94
Page 107
جان سکتا ہے کہ یہ شخص شدید بیمار ہے.بعینہ آج کے معاشرہ میں بیماری کے جملہ
آثار اور مرض کی تمام علامات صاف دکھائی دے رہی ہیں.حضرت مسیح علیہ السلام کا یہ قول کس قدر صداقت پر مبنی ہے.ان کے پھلوں سے تم ان کو پہچان لو گے.کیا کانٹے دار جھاڑیوں سے
کبھی انگور توڑے گئے ہیں اور کیا اونٹ کٹاروں سے کبھی انجیر میں بھی لی
گئی ہیں.اسی طرح اچھا درخت اچھے پھل لاتا ہے اور برا درخت برے
پھل لاتا ہے.اچھا درخت برا پھل نہیں لاسکتا نہ برا درخت اچھا پھل
متی باب ۷ آیات ۱۶ تا ۱۸)
لا سکتا ہے
"
آج جو کڑوے پھل کھانے کو مل رہے ہیں ان کے خلاف لوگ اپنے غم وغصہ کا
اظہار تو کرتے ہیں یہاں تک کہ چیخ چیخ کر ان کے گلے بیٹھ جاتے ہیں مگر وہ کڑوے
پھل دینے والے درخت کو بدلنا نہیں چاہتے.وہ نہیں چاہتے کہ اس کی جگہ میٹھے پھل
دینے والا درخت لگائیں.ان کے نزدیک اگر پھل کڑوا ہے تو درخت کا کوئی قصور
نہیں.اسلام کا معاشرتی نظام یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس شجرہ خبیثہ کو اکھاڑ کر اسکی بجائے
ایک طیب اور صحت مند درخت لگایا جائے.قرآن مجید کی رو سے جب آدم کو ایک
درخت کا پھل کھانے سے روکا گیا تو اس سے بعینہ یہی مراد تھی.قرآن کریم فرماتا
ہے.الَمْ تَرَكَيْفَ ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةِ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا
فِي السَّمَاءِ تُؤْتِى أُكُلَهَا كُلَّ حِيْنِ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَ يَضْرِبُ اللهُ الْأَمْثَالَ
لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذكَرُونَ
(سورۃ ابراہیم آیات ۲۵ - ۲۶)
ترجمہ.کیا تو نے غور نہیں کیا کہ کس طرح اللہ نے مثال بیان کی ہے ایک
کلمہ طیبہ کی ایک شجرہ طیبہ سے.اس کی جڑ مضبوطی سے پیوستہ ہے اور
95
95
Page 108
اس کی چوٹی آسمان میں ہے.وہ ہر گھڑی اپنے رب کے حکم سے اپنا
پھل دیتا ہے.اور اللہ انسانوں کے لئے مثالیں بیان کرتا ہے تا کہ وہ
نصیحت پکڑیں.اس آیت کریمہ میں شجرہ یعنی درخت کا لفظ ایک علامت کے طور پر استعمال ہوا
ہے.قرآن کریم نے بچے اور پاک فلسفہ کے بالمقابل غلط اور جھوٹے فلسفہ کا ذکر
کرتے ہوئے ایسی ہی علامتی زبان استعمال کی ہے.شجرہ طیبہ کے بالمقابل شجرہ خبیثہ
کا ذکر کیا گیا ہے.اس شجرہ خبیثہ اور ایمان نہ لانے والوں کی حالت کا ذکر اگلی دو
آیات میں آیا ہے.فرمایا:
و
ن
وَمَثَلُ كَلِمَةِ خَبِيثَةِ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةِ اجْتَتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارِ
يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ
الله الظَّلِمِينَ لا وَيَفْعَلُ اللهُ مَا يَشَاءُ ( سورۃ ابراہیم آیات ۲۷ - ۲۸)
ترجمہ.اور نا پاک کلمہ کی مثال نا پاک درخت کی سی ہے جو زمین پر سے
اکھاڑ دیا گیا ہو.اس کے لئے (کسی ایک مقام پر ) قرار مقدر نہ ہو.اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے مستحکم قول کے ساتھ دنیا اور آخرت میں
استحکام بخشتا ہے جبکہ اللہ ظالموں کو گمراہ ٹھہراتا ہے.اور اللہ جو چاہتا ہے
کرتا ہے.کلمہ کا لفظ یہاں ایک فلسفہ اور نظام کے معنوں میں استعمال ہوا ہے بالکل ایسے
ہی جیسے کلمہ کا یہ لفظ وسیع تر معنوں میں انجیل یوحنا کی پہلی آیت میں استعمال ہوا ہے.ابتداء میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا“
( یوحنا بابا آیت ا)
ان جھوٹے فلسفوں اور نظامہائے فکر کا انجام بھی لازما اس شجرہ خبیثہ کی طرح ہی
ہوتا ہے جو زندگی کے جہاد میں ناکام رہتا ہے اور بالآ خر تند و تیز ہواؤں اور طوفانوں
96
96
Page 109
کے ہاتھوں اکھاڑ پھینکا جاتا ہے.ہوائیں اسے اڑائے پھرتی ہیں.مگر اس کے برعکس
ایک صالح نظام اس شجرہ طیبہ کی طرح ہے جس کی جڑیں زمین میں مضبوطی سے قائم
ہیں اور اس کا تنا بلند اور شاخیں آسمان کی پاک فضاؤں اور وسعتوں میں پھیلی ہوئی
ہیں.یہ درخت آسمانی روشنی اور نور سے اپنی غذا حاصل کرتا ہے اور ہر موسم میں عمدہ
پھل لاتا ہے.قرآن کریم مومنوں کے متعلق فرماتا ہے کہ وہ ہستی باری تعالیٰ پر ایک
پختہ اور مضبوط ایمان رکھتے ہیں اور ان کے تمام اخلاق اور کردار کی جڑیں ایمان باللہ
کی زمین میں پیوست ہوتی ہیں.یہی وجہ ہے کہ اسلام میں اخلاق کا تصور اس قدر
کامل ہے کہ وہ سماجی، مذہبی اور نسلی سطح پر کوئی امتیاز روا نہیں رکھتا.وہ راہنما اصول جو انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں پر اطلاق پاتا ہے مندرجہ ذیل
آیت کریمہ میں بیان ہوا ہے:
ه و
وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّه فَاعْبُدُهُ وَ تَوَكَّلْ عَلَيْهِ.لیک
وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ
(سورۃ ہود آیت ۱۲۴)
ترجمہ.اور آسمانوں اور زمین کا غیب اللہ ہی کا ہے اور اسی کی طرف
معاملہ تمام تر لوٹایا جاتا ہے.پس اس کی عبادت کر اور اس پر تو کل کر.اور تیرا رب اس سے غافل نہیں ہے جو تم لوگ کرتے ہو.اسی طرح ایک اور آیت میں فرمایا.الَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ، تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَلَمِينَ (سورة الاعراف آیت ۵۵)
ترجمہ.خبردار! پیدا کرنا بھی اسی کا کام ہے اور حکومت بھی.بس ایک
وہی اللہ برکت والا ثابت ہوا جو تمام جہانوں کا رب ہے.ط
اسلام کا پیش کردہ یہ فلسفہ اللہ تعالیٰ کی کامل حاکمیت کے تصور سے شروع ہوتا ہے
اور اسی پر ختم ہوتا ہے.97
40
Page 110
اسلامی معاشرہ کے بنیادی اصول
اس موضوع پر قرآن کریم کی مرکزی آیت یہ ہے.10--
إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَابْتَايُّ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ( سورة النحل آیت ۹۱)
ج
ترجمہ.یقیناً اللہ عدل کا اور احسان کا اور اقرباء پر کی جانے والی عطا کی
طرح عطا کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی اور ناپسندیدہ باتوں اور بغاوت
سے منع کرتا ہے.وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تا کہ تم عبرت حاصل کرو.اس آیت کا پہلا حصہ سماجی نظام سے زیادہ معاشی امور سے متعلق ہے.اور
حصہ معاشرہ کے محروم طبقات سے سلوک کے بارے میں عدل احسان اور
ایتائے ذی القربی کے اسلامی تصور کی ایک واضح تصویر پیش کرتا ہے.آیت کے
دوسرے حصہ کا تعلق اس سماجی نظام سے ہے جو اسلام بہر صورت قائم کرنا چاہتا ہے.اس میں اللہ تعالیٰ نے ہر اس غلط کام سے روک دیا ہے جسے بالا تفاق ساری دنیا میں
غلط سمجھا جاتا ہے.مثلاً بدخلقی، کسی کی عزت پر حملہ، تو ہین اور درحقیقت وہ تمام سماجی
برائیاں جن کی کسی مذہبی تعلیم کے حوالہ کے بغیر وسیع تر انسانی معاشرہ میں بالاتفاق
مذمت کی جاتی ہے.اسی طرح اسلام ہر اس طرز عمل اور رجحان کو مسترد کرتا ہے اور
اس کی سختی سے مذمت کرتا ہے جو بدنظمی ، بغاوت اور تشدد پر منتج ہو.اس سیاق وسباق
میں ہر وہ بلا جواز حرکت بغاوت سمجھی جاتی ہے جو کسی بھی قائم اور مستحکم نظام کو منہدم
کرنے کے لئے کی جائے.صرف یہی نہیں بلکہ قرآن کریم میں جب بھی عربی لفظ
”بغی“ استعمال ہوا ہے اس کا اطلاق صرف مسلح یا سیاسی بغاوت پر ہی نہیں ہوتا بلکہ
یہ لفظ معاشرہ کی ارفع و اعلیٰ روایات، اخلاقی اقدار اور مذہبی تعلیمات کے خلاف سر
اٹھانے پر بھی اطلاق پاتا ہے.98
Page 111
آیت کے آخری حصہ میں واضح طور پر تنبیہ کر دی گئی ہے کہ یہ نصیحت انسان کے
اپنے فائدہ کے لئے ہی کی گئی ہے.یوں اس بنیادی اور مرکزی آیت میں اسلام کے
سماجی نظام کے اہم خدو خال واضح کر دیئے گئے ہیں.یہ بھی یادر ہے کہ اس آیت کا
پہلا حصہ بھی اسلام کی معاشرتی تعلیمات سے گہرا ربط رکھتا ہے.ایک ایسا معاشرہ
جسے دوسرے انسانوں کی تکالیف کا احساس نہ ہو اور جو انسانیت کی خدمت کے دائمی
ا
جذبہ سے خالی ہو ہرگز اسلامی معاشرہ نہیں کہلا سکتا خواہ اسلام کی سماجی تعلیمات کے
دوسرے پہلوؤں سے وہ کتنی ہی مطابقت کیوں نہ رکھتا ہو.آئیے اب ہم اسلامی معاشرہ کی بعض اور خصوصیات کا مطالعہ کرتے ہیں جن
کا نقشہ قرآن کریم نے کھینچا ہے.اسلام نے اخلاص، دیانت داری اور وفا شعاری پر
بڑا زور دیا ہے.اسلام ہر اس امر اور اقدام کی حوصلہ افزائی کرتا ہے جس کے نتیجہ
میں معاشرہ میں ذہنی اور قلبی آسودگی پیدا ہوتی ہے.عیش وعشرت کی تلاش جس قسم
کے معاشرتی بگاڑ اور عدم توازن پر منتج ہو سکتی ہے اسے روکنے کے لئے بھی کئی تدابیر
اختیار کی گئی ہیں.ہر ایسے طرز عمل کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے جو معاشرہ کو بے لگام
جنسی آزادی کی طرف لے جا سکتا ہے خواہ آغاز میں وہ کتنا ہی بے ضرر کیوں نہ
دکھائی دے.جنسی آزادی کئی طرح سے معاشرہ کو بے پناہ نقصان پہنچاتی ہے اور اس
کا انجام اس مادر پدر آزاد جنسی بے راہ روی پر ہوتا ہے جس نے آج دنیا کو اپنی
لپیٹ میں لے رکھا ہے.لذات کے پیچھے اندھا دھند بھاگنے سے دیگر نقصانات کے
علاوہ ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ خاندانی رشتے ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جاتے ہیں.اس کے برعکس اسلام ماں باپ، بھائی، بہن اور اولاد کے مقدس رشتوں کو بہت اہمیت
دیتا ہے اور ان کی حفاظت کرتا ہے.اسی طرح اسلام ان دوستانہ تعلقات کو بھی فروغ
دیتا ہے جو ہوس پرستی کی بجائے پاکیزہ محبت پر مبنی ہوں.99
80
Page 112
عفت اور یا کدامنی
اسلام کے نزدیک معاشرہ میں خواتین کی عزت و احترام کے قیام کیلئے یہ امر
از حد ضروری ہے کہ ایسے تمام اقدامات کئے جائیں جو عفت وفاشعاری ضبط نفس اور
پاکیزہ زندگی کو فروغ دیں.جنسی بے راہ روی کے خطرات سے پوری طرح محفوظ
رہتے ہوئے پاک و صاف زندگی بسر کرنا اسلامی معاشرہ کا ایک بہت اہم وصف
ہے.اسلام کی پیش کردہ سماجی تعلیمات کا یہ پہلو خاندانی نظام کی بقا اور حفاظت کیلئے
انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور یہی آج کے دور کی ایک اہم ترین ضرورت بھی ہے.اسلام فیملی یونٹ کو محض میاں بیوی کے تعلق تک محدود نہیں رکھنا چاہتا بلکہ اسے
وسعت دینا چاہتا ہے.ایک ایسا خاندان جس میں پیار اور محبت کا تصور محض جنسی
خواہشات کی تکمیل تک ہی محدود نہ ہو بلکہ اس میں دیگر خونی رشتوں کی سی گہری اور
لطیف رفاقتیں بھی موجود ہوں.حیرت ہے کہ عصر حاضر کے دانشور کیوں اس
خطرناک انسانی کمزوری سے ناواقف ہیں کہ اگر معاشرہ میں جنسی لذات کے حصول
کی کھلی چھٹی مل جائے تو پھر بے حیائی کا عفریت اعلیٰ اور لطیف اقدار کا خون چوس
چوس کر بڑھنا اور پھیلنا شروع ہو جاتا ہے.سگمنڈ فرائڈ (Sigmond Freud)
ایک ایسے ہی معاشرہ کی پیداوار ہے.وہ ہر انسانی جذبہ اور عمل کو جنسی پیمانہ سے پرکھتا
ہے.اس کے نزدیک ماں اور بچے کا مقدس ترین رشتہ بھی جنسی جذبات ہی سے تعلق
رکھتا ہے.اسی طرح باپ اور بیٹی کے رشتہ کو بھی کوئی تقدس حاصل نہیں بلکہ یہ بھی
جنسی خواہشات ہی کا شاخسانہ ہے.بقول اس کے انسان کا تقریبا ہر عمل جسکا اسے
شعوری طور پر علم ہو یا نہ ہو اسکی گہری لاشعوری جنسی خواہشات کا آئینہ دار ہوتا ہے.میں نہیں جانتا کہ فرائڈ کے اپنے زمانہ میں بھی آج کے معاشرہ کی سی جنسی
بے راہ روی عام ہو چکی تھی یا نہیں پھر بھی اتنا فساد ضرور تھا جس کی روشنی میں اس نے
100
Page 113
انسانی نفسیات اور جنس سے متعلق اپنا مخصوص نظریہ قائم کیا.اگر فرائڈ کی سوچ کو
درست بھی مان لیا جائے تو یہ امر اور بھی ضروری ہو جاتا ہے کہ ایسے طاقتور اور
خطر ناک محرکات کو بلا روک ٹوک کھل کھیلنے کا کوئی موقع نہ دیا جائے.ورنہ ظاہر ہے
کہ انسانی ذہن ضرور کسی نہ کسی غلط رستہ پر چل نکلے گا.افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ اسلام کے پیش کردہ معاشرتی ماحول اور اس کی خوبیوں
کو سمجھنا تو در کنار عصر حاضر کا معاشرہ اس سلسلہ میں کوشش کرنے کے لئے بھی تیار
نہیں.مگر یاد رہے کہ انسان نہ تو اللہ تعالیٰ کے فعل یعنی قوانین قدرت کو شکست دے
سکتا ہے اور نہ ہی اس کے قول یعنی کلام الہی کو جھٹلا سکتا ہے.خواہ وہ تقدیر کے خالق
اور مالک اور مقتدر بالا رادہ ہستی پر ایمان رکھے یا نہ رکھے.اور خواہ انسان کلام الہی
کے مطابق اپنے سماجی کردار کی تشکیل پر آمادہ ہو یا نہ ہو یہ بات یقینی ہے کہ وہ
اللہ تعالیٰ کے قول اور فعل کو جھٹلا نہیں سکتا.اللہ تعالیٰ کے فعل اور اس کے کلام کو تب ہی
برحق سمجھا جائے گا جب دونوں میں کامل موافقت اور ہم آہنگی ہو.پس انسان کا ہر وہ
معاشرتی رویہ جو کلام الہی سے متصادم ہو لا ز ما تباہی اور بربادی پر منتج ہوگا.انسان بلا روک ٹوک ہمیشہ عیش وعشرت کی زندگی بسر نہیں کر سکتا خواہ وہ اس کے
لیئے کتنی ہی خواہش کیوں نہ کرے.اسے زیادہ سے زیادہ یہی اختیار دیا گیا ہے کہ
بعض چیزوں کو پسند کرے اور بعض کو ترک کر دے.وہ معاشرہ جو افیون اور دیگر
منشیات کو اپنا لیتا ہے اور زندگی کے حقائق اور ذمہ داریوں سے فرار اختیار کر لیتا ہے
وہ معاشرہ جو شہوات، عیاشی اور سنسنی خیزی کے جنون میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ معاشرہ
جہاں عمد لوگوں کے ذوق بگاڑے جاتے ہیں اور انہیں زیادہ سے زیادہ عیش وعشرت
کا دلدادہ بنایا جاتا ہے تا کہ نت نئے آلات و سامان عیش وعشرت کی مصنوعی مارکیٹ
پیدا ہو سکے اور هَلْ مِنْ مَّزِيْدِ کی ہوس بڑھتی چلی جائے تا کہ اس سے بڑی بڑی
101
Page 114
کاروباری کمپنیوں کا دولت کے انبار اکٹھے کرنے کا واحد مقصد پورا ہوتا رہے ایسا
معاشرہ یہ سب کچھ تو حاصل کر لیتا ہے مگر اسے اس کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑتی
ہے.اطمینان قلب اٹھ جاتا ہے، اعلیٰ قدریں ختم ہو جاتی ہیں اور معاشرہ کا مجموعی
امن وسکون برباد ہو جاتا ہے.ظاہر ہے کہ عیش پرستی اور دل کا اطمینان دونوں کبھی
اکٹھے نہیں ہو سکتے.ایک مادہ پرست معاشرہ جن اعلیٰ اقدار کو نظر انداز کرتا ہے اسلام انہیں کے قیام
پر زور دیتا ہے.لذت کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے لیکن اسے ذہنی سکون اور معاشرتی
امن کی قیمت پر خریدا نہیں جا سکتا.ایسے تمام رجحانات جن کے باعث رفتہ رفتہ
خاندان ٹوٹ جایا کرتے ہیں اور خود غرضی، غیر ذمہ داری، بے ہودگی، تشدد اور جرائم کو
فروغ ملتا ہے انکی اسلام نے حوصلہ شکنی کی ہے.اسلامی فلسفہ جس معاشرتی ماحول کو جنم
دیتا ہے اس میں اور مادہ پرستی کے ماحول میں زمین و آسمان کا فرق ہے.مجھے حیرت
ہوتی ہے کہ کچھ لوگ اس حقیقت کو کیوں فراموش کر دیتے ہیں کہ خواہشات کو ہوا
دینے یا کھلی چھٹی دینے سے انہیں ذہنی اور قلبی اطمینان ہرگز نصیب نہیں ہوسکتا.اور
دنیا کا کوئی معاشرہ بھی خواہ وہ اقتصادی لحاظ سے کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو بے لگام
خواہشات اور ہوس پرستی کا ہرگز متحمل نہیں ہوسکتا.دنیا کے متمول ترین معاشروں میں بھی آسودہ حال لوگوں کے ساتھ ساتھ
مفلوک الحال لوگ بھی موجود ہیں.اور ایسے لوگوں کی تعداد جو زندگی کی بنیادی
سہولتوں سے محروم ہوں ہمیشہ بہت زیادہ ہوتی ہے.اس کے بالمقابل ایسے خوشحال
لوگ تو بہت کم ہوا کرتے ہیں جو اپنی ہر خواہش پوری کر سکیں.دراصل ہر خواہش کی
تسکین ویسے بھی ممکن نہیں کیونکہ دولت کے ساتھ ساتھ خواہشات بھی بڑھتی چلی جاتی
ہیں اس لئے امیر ترین لوگوں کے بھی سب خواب پورے نہیں ہو سکتے.عین ممکن ہے
102
Page 115
تکتے
کہ وہ بھی حسرتوں اور محرومیوں کی آگ میں جل رہے ہوں لیکن غرباء کی حالت تو
بہت ہی ابتر ہوتی ہے.زندگی کی بنیادی سہولتیں حاصل کرنا بھی ان کی پہنچ سے باہر
ہوتا ہے کجا یہ کہ وہ امراء کی سی عیاشی کے متحمل ہوسکیں.ٹی وی اور اخبارات وغیرہ
میں جب اس قسم کی شاہانہ زندگی کی جھلکیاں دکھائی جاتی ہیں تو یہی غرباء ہیں جن کے
احساسات مجروح ہوتے ہیں اور جن کی آرزوؤں کا دم گھٹنے لگتا ہے.یہ غریب لوگ
اپنے بوسیدہ مکانوں میں بیٹھے ہر روز عالی شان گھروں، شاندار باغات، پرتعیش
کاروں، ہیلی کا پڑوں، ذاتی جہازوں، نوکروں اور خدمتگاروں کی فوج کو حیرت اور
رہتے ہیں.جب یہ غریب لوگ ہالی وڈ اور بیورلے ہلز
(Beverley Hills) کا طرز زندگی ، ناچ گانے اور رقص و سرود کی محفلیں، دھوم
دهام.سے منعقد ہونے والی تقریبات یا قمار خانوں میں زندگی کے رنگ ڈھنگ
دیکھتے ہیں تو ان کے دل حسرتوں اور محرومیوں کی آماجگاہ بنتے چلے جاتے ہیں.وہ
سراب جن کی منظرکشی ٹی وی ڈراموں میں کی جاتی ہے غریبوں کے خواب بن جاتے
ہیں کیونکہ ٹی وی اور اس کے ڈرامے ہی تو ہیں جو یہ بے بس اور بیچارے لوگ دیکھ
سکتے ہیں.دوسری طرف حقیقت یہ ہے کہ امیر ترین لوگوں میں سے بھی صرف گنتی کے
چند لوگ ہی ہیں جو اس جنت ارضی کو حاصل کر سکتے ہیں.لیکن یہ غریب لوگ
عیش وعشرت کے یہ مناظر دیکھ کر اپنے فلاکت زدہ ماحول سے ہی بددل ہو جاتے
ہیں.اپنے گھروں میں ان کے لئے کوئی کشش باقی نہیں رہتی.ایک طرف وہ اعلیٰ
تہذیب و تمدن سے محروم ہوتے ہیں اور دوسری طرف دن رات سنہری خوابوں میں
کھوئے رہتے ہیں.اور یوں ان کی اپنی زندگی کے حقائق بے معنی ہوتے چلے جاتے
ہیں.بے سود لذتوں اور پر فریب خوابوں پر تعمیر ہونے والے معاشرہ کا انجام کار حاصل
یہی ہے.گھر میں امن وسکون اور ایک دوسرے کے لئے محبت و اخلاص کی گرمجوشی
103
Page 116
رفتہ رفتہ ایک سراب بن کر رہ جاتی ہے.پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ایسے لوگ یہ بھی
نہیں جانتے کہ وہ کس کی خاطر زندگی بسر کریں اور کس امید پر زندگی کے ماہ و سال
کاٹیں.اب اگر ہم نے ان پیارے گھروں کو پھر سے قائم کرنا ہے جو کبھی پہلے ہوا کرتے
تھے، اس باہمی اعتماد کو بحال کرنا ہے جو گھر کے افراد کو یک جان کر دیتا ہے اور اس
اعتبار کو قائم کرنا ہے جو باہمی امن وسکون اور محبت کو جنم دیتا ہے تو اس کے لئے کئی
اقدامات کرنے پڑیں گے.مگر شاید اب دیر ہو چکی ہے اور پانی سر سے گزر چکا ہے.اس ضمن میں اسلام کا پیغام بڑا واضح ہے.اسلام خاندانی نظام کی حفاظت یا جہاں
کہیں بھی یہ نظام ٹوٹ کر بکھر چکا ہو اسے از سر نو قائم کرنے کے لئے واضح پروگرام
رکھتا ہے.اسلام کے نزدیک زندگی کے ہر دائرہ میں نظم و ضبط کو سکھانے کے لئے
ضروری ہے کہ سمجھ بوجھ ، حکمت و دانائی اور محکم ایمان و اعتقاد کو کام میں لایا جائے
اور معاشرہ میں پائے جانے والے عدم توازن کو دور کیا جائے.پردہ اور اس کی حقیقت
اسلام میں پردہ کے معاشرتی نظام کو مغرب میں لوگوں نے بالکل غلط سمجھا ہے.ان کے نزدیک اس طرح مردوں اور عورتوں میں ایک جنسی امتیاز روا رکھا گیا ہے.غلط فہمی ایک حد تک عالم اسلام میں اسلام کی اصل تعلیم پر غلط رنگ میں عمل پیرا
ہونے کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے.اس غلط فہمی کی دوسری وجہ مغربی ذرائع ابلاغ کا
منفی کردار ہے جنکی یہ عادت بن چکی ہے کہ جہاں کہیں کوئی بدعملی اور بدکرداری
دکھائی دی اسے فوراً اسلام کی طرف منسوب کر دیا.حالانکہ کسی یہودی، عیسائی، بدھ یا
ہندو کے غلط کردار کو اس کے مذہب کی طرف کبھی منسوب نہیں کیا جاتا.104
Page 117
اسلام میں پردہ کا حکم زمانہ جاہلیت کی کسی تنگ نظری کی پیداوار نہیں ہے.حقیقت یہ ہے کہ پردہ کا رواج یا عورتوں اور مردوں کے آزادانہ میل جول کا رجحان
زمانہ کی ترقی یا پسماندگی سے کوئی تعلق نہیں رکھتا.تاریخ عالم میں ہمیشہ سے ایسا ہوتا
آیا ہے کہ معاشرتی تمدن کی ناؤ مذہبی یا سماجی لہروں کے مدوجزر کے ساتھ ساتھ آگے
بڑھتی رہی ہے.آزادی نسواں کا تصور بھی کوئی ایسا رجحان نہیں ہے جو رفتہ رفتہ پیدا ہوا ہو.اس
امر کی قوی شہادتیں موجود ہیں کہ بہت قدیم زمانوں میں بھی اور ماضی قریب میں بھی دنیا
کے مختلف خطوں میں طبقہ نسواں معاشرہ میں بہت طاقتور اور غالب حیثیت کا مالک رہا
ہے.اسی طرح مردوں اور عورتوں کا آزادانہ اختلاط ہرگز کوئی نئی اور عجیب بات نہیں
ہے.تہذیبیں دنیا میں ابھرتی اور مٹتی رہتی ہیں.انسانی عادات و اطوار اور فیشن بھی آئے
دن بدلتے رہتے ہیں.نہ جانے کتنے ہی سماجی رجحانات نت نئے تجربات میں سے گزر
کر بنتے ہیں اور بگڑتے رہتے ہیں اور تہذیب انسانی ہر آن ایک نیا منظر پیش کرتی رہی
ہے.یہ کوئی ایسا دائگی اور مستقل رجحان نہیں جس سے ہم یہ حتمی نتیجہ نکال سکیں کہ انسانی
تاریخ نے ہمیشہ ایک باپردہ معاشرہ سے مخلوط معاشرہ کی سمت میں ہی سفر کیا ہے یا عورتیں
چادر اور چار دیواری کی قید سے آزادی نسواں کی منزل کی طرف بڑھتی رہی ہیں.حقوق نسواں کے ایک نئے دور کا آغاز
یہاں مناسب ہوگا کہ ہم تاریخ عرب کے اس تاریک دور کا جائزہ لیں جس میں
اسلام کا ظہور ہوا.مسلمانوں کے عقیدہ کے مطابق اسلام کا پیغام وحی الہی پر مبنی تھا.اس کے برعکس غیر مسلموں کے نزدیک یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خود ساختہ تعلیم
105
Page 118
تھی.مذہبی علماء کا اس کے متعلق جو بھی نظریہ ہو یہ امر واقعہ ہے کہ پردہ کے متعلق
اسلام کی تعلیم کا عربوں کے مروجہ طریق سے دور کا بھی تعلق نہیں.اسلام کے ظہور
کے وقت عرب معاشرہ عورتوں کے متعلق بہت متضاد رویوں کا حامل تھا.ایک طرف
جنسی آزادی اور عورتوں اور مردوں کا آزادانہ میل جول تھا جبکہ شراب عورت اور
گانے بجانے کا جنون اس معاشرہ کی نمایاں خصوصیات تھیں اور دوسری جانب لڑکی کی
پیدائش کو سخت بے عزتی اور شرم کا باعث سمجھا جاتا تھا.بعض عرب لوگوں نے فخر سے
بیان کیا ہے کہ انہوں نے اس ذلت سے بچنے کے لئے اپنی نوزائیدہ بیٹیوں کو زندہ
درگور کر دیا.عورت کی حیثیت جائیداد منقولہ سے بڑھ کر نہیں تھی.اسے یہ حق حاصل نہیں تھا
کہ وہ اپنے خاوند یا باپ یا خاندان کے کسی دوسرے فرد سے اختلاف کر سکے.ا
بے شک اس عام روش سے ہٹ کر استثنائی مثالیں بھی ملتی ہیں.کبھی کبھار ایسا بھی
ہوتا تھا کہ شاندار قائدانہ صلاحیتیں رکھنے والی عورت اپنے قبیلہ میں ایک نمایاں مقام
حاصل کر لے.اسلام نے اس ساری معاشرتی صورت حال
کو یکسر تبدیل کر دیا اور یہ
تبدیلی کسی معاشرتی کشیدگی اور تناؤ کے نتیجہ میں پیدا ہونے والا طبعی رد عمل نہیں تھا
بلکہ اسلام نے حکم اور عدل کے طور پر نئی اقدار دنیا میں قائم فرما ئیں.ایک نیا
سماجی نظام بذریعہ وحی الہی عطا کیا گیا.یہ نیا نظام ان محرکات کا مرہون منت نہیں تھا
جو عموماً معاشرہ کی تشکیل کیا کرتے ہیں.پردہ کی تعلیم کے نتیجہ میں جنسی بے راہ روی فوری طور پر رک گئی.مرد اور عورت
کے تعلقات کو ایک ایسے نظام کا پابند بنا دیا گیا جو پائیدار اور اخلاقی اصولوں پر مبنی
تھا.اس کے ساتھ ساتھ عورت کے مقام اور مرتبہ کو اتنا بلند کر دیا گیا کہ یہ ممکن ہی نہ
رہا کہ کوئی اسے بے بس اور بے جان مخلوق سمجھ کر اس سے اشیائے صرف کا سا سلوک
106
Page 119
کرے.زندگی کے تمام معاملات میں اسے مردوں کے مساوی حقوق عطا کئے گئے.اسلام سے پہلے عورتیں وراثت میں تقسیم ہوا کرتی تھیں مگر اب عورت نہ صرف اپنے
باپ کی جائیداد کی وارث ہو سکتی تھی بلکہ اپنے خاوند بچوں اور دیگر رشتہ داروں کی
جائیداد کی شرعاً وارث قرار دی گئی.اب وہ دلیری کے ساتھ اپنے خاوند کی رائے
سے اختلاف کر سکتی تھی.بے خوف و خطر اس سے بحث کر سکتی تھی اور اسے اپنی رائے
پر قائم رہنے کا پورا حق حاصل تھا.اب صرف عورت ہی کو طلاق نہیں دی جا سکتی تھی
بلکہ عورت چاہے تو وہ مرد کو طلاق دے سکتی تھی.عورت کو بحیثیت ماں اسلام نے جس
تعظیم و تکریم کا مستحق ٹھہرایا ہے دنیا کے دوسرے معاشروں میں اس کی مثال ملنی محال
ہے.حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات تھی جس نے
حقوق نسواں کے قیام کے لئے وحی الہی کے ماتحت یہ اعلان فرمایا."
66
” تمہاری جنت تمہاری ماؤں کے قدموں تلے ہے
اس ارشاد میں آپ نے صرف اس جنت ہی کے وعدہ کا ذکر نہیں فرمایا جو آئندہ
زندگی میں پورا ہوگا بلکہ ایک ایسی معاشرتی جنت کا ذکر بھی کیا ہے جس کا وعدہ ان
لوگوں سے ہے جو اپنی ماؤں کے ساتھ انتہائی عزت و احترام سے پیش آتے ہیں اور
انہیں ہر ممکن راحت اور آرام پہنچانے کے لئے کوشش کرتے رہتے ہیں.پردہ سے متعلق اسلامی تعلیم کو اسی سیاق و سباق میں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہئے.اسلام یہ تعلیم اس لئے نہیں دیتا کہ مرد کو عورت پر کوئی مزعومہ برتری یا فوقیت حاصل
ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم اس لئے دی ہے تا کہ گھر یعنی چادر اور چار دیواری کا
تقدس قائم ہو خاوند بیوی کے درمیان باہمی اعتماد کی فضا پروان چڑھے اور طبعی
خواہشات اور جذبات کو اعتدال پر لایا جائے اور انہیں معاشرہ میں یوں بے لگام نہ
چھوڑ دیا جائے کہ وہ ایک خوفناک عفریت بن کر رہ جائیں بلکہ انہیں اس طرح قابو
107
Page 120
میں لایا جائے جس سے وہ فطرت کی دیگر منظم قوتوں کی طرح ایک تعمیری کردار ادا
کرسکیں.پردہ کی اس اسلامی تعلیم کے متعلق بڑی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں.اسے ایک
ایسی پابندی تصور کیا جاتا ہے جس کے نتیجہ میں خواتین زندگی کے جملہ شعبوں میں
بھر پور شمولیت سے محروم ہو جائیں.حالانکہ یہ بات ہرگز ہرگز درست نہیں ہے.پردہ
کے اسلامی تصور کو سمجھنے کے لئے اس کے مقصد کو سمجھنا بے حد ضروری ہے.پردہ کا
مقصد یہ ہے کہ عورت کی عزت اور عصمت کے تقدس کی حفاظت کی جائے اور معاشرہ
میں اس کے احترام کو قائم کیا جائے.پردہ ان خطرات کے خلاف تحفظ فراہم کرتا ہے
جن سے عورت کی عزت و عصمت پر حرف آ سکتا ہے.یہی وجہ ہے کہ اسلامی معاشرہ
میں نامحرم مرد اور عورت کے آزادانہ میل جول اور تعلقات اور معاشقوں کی سختی سے
حوصلہ شکنی کی گئی ہے.مرد اور عورت کو نہ صرف بدنظری سے روکا گیا ہے بلکہ ایسے تمام
مناظر کو دیکھنے اور جسمانی قرب بلکہ لمس تک سے منع کیا گیا ہے جس کے نتیجہ میں
ایسے منہ زور جذبات برانگیختہ ہو جائیں جن پر قابو پانا عام انسان کے بس میں نہ ہو.عورتوں سے یہ توقع کی گئی ہے کہ وہ اپنے جسم کو عمدگی کے ساتھ ڈھانپ کر رکھیں گی.انہیں یہ نصیحت کی گئی ہے کہ وہ ایسا انداز اور ایسا رنگ ڈھنگ اختیار نہ کریں جس کے
نتیجہ میں کسی آوارہ مزاج مرد کو بری نظر سے دیکھنے کا موقع مل سکے.بناؤ سنگھار کرنا
اور زیورات پہنا ممنوع نہیں ہے لیکن گھر سے باہر نامحرم مردوں کی توجہ حاصل کرنے
کے لئے زیب و زینت اختیار کرنا درست نہیں ہے.ہم یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں موجودہ معاشرتی مزاج اور اطوار کے
لحاظ سے یہ تعلیم سخت دکھائی دیتی ہے.اس میں بہت سی پابندیاں ہیں اور بظاہر یہ بے
رنگ اور بے کیف سی نظر آتی ہے تاہم اسلام کے سارے سماجی نظام کے بنظر غائر مطالعہ
108
Page 121
.سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ رائے جلدی میں قائم کی گئی ہے اور اس میں سطحیت پائی جاتی
ہے.ضروری ہے کہ پردہ کی تعلیم کو اسلام کے پیش کردہ مجموعی اخلاقی نظام اور سماجی
ماحول کا ایک لازمی جزو سمجھا جائے جس سے الگ کر کے اسے سمجھا ہی نہیں جاسکتا.اسلام کے سماجی نظام میں عورتوں کا کردار محلات میں رکھی جانے والی لونڈیوں کا
سانہیں ہے.نہ ہی عورت کو گھر کی چاردیواری میں مقید کیا گیا ہے اور نہ اسے ترقی اور
علم کی روشنی سے محروم رکھا گیا ہے.اسلام کے سماجی نظام کی یہ بھیانک تصویر دراصل
اسلام کے اندرونی اور بیرونی دشمنوں کی بنائی ہوئی ہے یا پھر اسے ان ملاؤں کی طرف
منسوب کیا جا سکتا ہے جو اسلامی طرز حیات کو سمجھنے کی استعداد ہی نہیں رکھتے.ایک بات تو طے ہے کہ اسلام یہ اجازت نہیں دے سکتا کہ عورت کو کھلونا سمجھ کر
اس کا استحصال کیا جائے اور وہ مرد کی ہوس کا نشانہ بنتی رہے.اسلام عورت کے متعلق
ایسا تو ہین آمیز طرز عمل روا ر کھنے کی قطعاً اجازت نہیں دیتا.کیا یہ انتہائی ظلم نہیں کہ چونکہ معاشرہ کا مزاج تقاضا کرتا ہے اس لئے یہ ضروری
سمجھا جائے کہ عورت اپنے آپ کو بنا سنوار کر رکھے اور پرکشش نظر آنے کی کوشش
کرتی رہے.عورت کے ساتھ آج یہ ظلم ہو رہا ہے.ہر وقت نسوانی حسن کی نمائش کی
جاتی ہے.کھانے پینے کی کوئی چیز روزمرہ کی اشیائے صرف مثلاً واشنگ پاؤڈر وغیرہ
تک کو فروخت کرنے کے لئے ضروری ہو گیا ہے کہ اشتہار میں عورت کی چہرہ نمائی کی
گئی ہو.دوسری طرف زندگی کے مصنوعی ٹھاٹ باٹ کو یوں پیش کیا جاتا ہے جیسے اس
کے بغیر عورت کے خوابوں کی تعبیر ممکن ہی نہ ہو.ایسا معاشرہ کبھی زیادہ دیر تک
متوازن اور صحت مند نہیں رہ سکتا.اسلامی تعلیم کے مطابق خواہ کچھ بھی ہو عورت کو
استحصال سے بہر حال آزادی ملنی چاہئے.اسے اس بات سے نجات ملنی چاہئے کہ وہ
مرد کے لئے محض حصول لذت کا ذریعہ بنی رہے.اس کے پاس خود اپنے لئے کچھ
109
Page 122
فارغ وقت ہونا چاہئے تاکہ وہ اپنے گھر اور آنے والی نسلوں سے متعلق اپنی
ذمہ داریاں ادا کر سکے.عورتوں کے لئے مساوی حقوق
آج کل آزادی نسواں اور حقوق نسواں وغیرہ کا بہت چرچا ہے.اسلام اس کے
متعلق ایک ایسا جامع اور بنیادی اصول بیان کرتا ہے جو اس مسئلہ کے تمام ممکنہ
پہلوؤں پر حاوی ہے.اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے.280
وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ، وَاللَّهُ عَزِيزٌ
حکیم
(سورۃ البقره آیت ۲۲۹)
ترجمہ.اور ان (عورتوں) کا دستور کے مطابق ( مردوں پر ) اتنا ہی حق
ہے جتنا (مردوں کا) ان پر ہے.حالانکہ مردوں کو ان پر ایک قسم کی
فوقیت بھی ہے.اور اللہ کامل غلبہ والا (اور) حکمت والا ہے.قرآن کریم ایک اور آیت میں فرماتا ہے:
الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا
مِنْ أَمْوَالِهم
(سورۃ النساء آیت ۳۵)
ترجمہ.مرد عورتوں پر نگران ہیں اس فضیلت کی وجہ سے جو اللہ نے ان
میں سے بعض کو بعض پر بخشی ہے.اور اس وجہ سے بھی کہ وہ اپنے اموال
(ان پر ) خرچ کرتے ہیں.اس آیت میں عربی لفظ قوام کے معنی نگر ان کے ہیں جو اپنے زیر نگرانی افراد کو
صحیح رستہ پر چلانے کا ذمہ دار ہو.لیکن دقیا نوسی ذہنیت رکھنے والے علماء لفظ قوام
110
Page 123
سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں اور اس امر کا دعویٰ کرتے ہیں کہ مردوں کو عورتوں پر برتری
حاصل ہے.حالانکہ اس آیت میں مردوں کی صرف اس فضیلت کا ذکر ہے جو ایک
کمانے والے کو اپنے زیر کفالت فرد پر حاصل ہوتی ہے.اس لحاظ سے ایک نگران
اور سر پرست اس بات کا ذمہ دار ہے کہ وہ اپنے زیر کفالت افراد کی بہتر رنگ میں
اخلاقی تربیت کرے.جہاں تک بنیادی انسانی حقوق کا سوال ہے اس آیت میں ہرگز یہ بیان نہیں کیا
گیا کہ عورتیں مردوں کے برابر نہیں ہیں نہ ہی اس میں مردوں کی عورتوں پر برتری کا
ذکر ہے.البتہ آیت کے آخری حصہ میں مردوں کی اس فضیلت کا ذکر ہے جو بحیثیت
نگران انہیں حاصل ہے.اس سے یہ بات کھل کر سامنے آجاتی ہے کہ عورتوں
اور مردوں کے بنیادی حقوق بالکل مساوی ہیں.اس لحاظ سے اس آیت میں مذکور
عربی حرف و کا ترجمہ اس حقیقت کے باوجود کہ “ یا ” جبکہ ہوگا.اس سیاق و سباق
میں یہی درست ترجمہ ہے.تعدد ازدواج
مغرب میں اسلام کے موضوع پر بات کی جائے تو اکثر اوقات یہ سوال پوچھا
جاتا ہے کہ کیا اسلام چار شادیاں کرنے اور بیک وقت چار بیویاں رکھنے کی اجازت
دیتا ہے.مجھے مغربی دنیا میں جلسوں اور چوٹی کے دانشوروں سے خطاب کرنے کا
موقع ملتا رہتا ہے.بہت کم ایسے مواقع مجھے یاد ہیں جب کہ اس قسم کا سوال نہ اٹھایا
گیا ہو.بارہا ایسا ہوا کہ کوئی نہ کوئی خاتون بڑے معذرت خواہانہ انداز میں اور بڑی
معصومیت سے یہ سوال دہرایا کرتی ہیں کہ کیا واقعی اسلام چار شادیوں کی اجازت
111
Page 124
دیتا ہے.جہاں تک اس سوال کے جواب کا تعلق ہے تو یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں
اور غالباً اسلام کا یہی ایک پہلو ہے جس سے اہل مغرب کی بہت بڑی تعداد آشنا
ہے.اسلام کے جس دوسرے پہلو سے مغرب میں لوگ آگاہ ہیں وہ دہشت گردی
ہے.حقیقت یہ ہے کہ دہشت گردی کا اسلام سے دُور کا بھی تعلق نہیں ہے.(ملاحظہ ہو مقرر کی کتاب ”مذہب کے نام پر خون).ہے.مذکورہ بالا سوال اس رنگ میں بھی پوچھا جاتا ہے کہ مرد اور عورت کے درمیان یہ
کیسی مساوات ہے جو اسلام پیش کرتا ہے کہ مرد کو چار بیویوں کی اجازت ہے جبکہ
عورت صرف ایک خاوند کر سکتی ہے.میرا خیال ہے کہ ایسے سوالات اسلام کے متعلق
وہ سارا اچھا تاثر زائل کرنے کے لئے پوچھے جاتے ہیں جو میں اس مجلس میں قائم
کرتا ہوں.نسبتا کم رسمی محفلوں میں جہاں شائستگی اور آداب کا زیادہ خیال نہیں رکھا
جاتا وہاں یہ سوال استفسار کی بجائے تمسخر اور استہزاء کا رنگ اختیار کر لیتا ہے.بہت
عرصہ پہلے کی بات ہے جب میں لندن یونیورسٹی کے سکول آف اور پیٹل اینڈ
افریقن سٹڈیز میں پڑھتا تھا وہاں ایک پاکستانی طالب علم کا اس کے انگریز ساتھی نے
یہی سوال پوچھ پوچھ کر ناک میں دم کر رکھا تھا.وہ ہر بار ایک قہقہہ لگا کر یہ سوال
پوچھتا تھا.مجھے یاد ہے جب ایک مرتبہ اس پاکستانی طالب علم کو بہت ہی دق کیا گیا
تو اچانک اس نے پلٹ کر جواب دیا کہ تم ہماری چار ماؤں کے ہونے پر اعتراض
کرتے ہو جبکہ تمہارے اپنے چار چار باپ ہوتے ہیں.اس مفہوم کو ادا کرنے کے
لئے اس نے کمال ذہانت سے Forefathers کا لفظ استعمال کیا یعنی آباؤ اجداد.بولنے میں یہ لفظ ذو معنی ہے کیونکہ اس سے مراد Fourfathers یعنی چار باپ بھی
لیا جا سکتا ہے.پس اس طرح اس نے اپنے مدمقابل کو ایسی زک پہنچائی کہ اس
انگریز کی ظاہری جیت ہار سے بدل گئی.112
Page 125
بظاہر یہ ایک لطیفہ نظر آتا ہے لیکن غور سے دیکھا جائے تو محض لطیفہ ہی نہیں بلکہ
بعض حقائق کو خوب بے نقاب بھی کرتا ہے.یہ لطیفہ ایک افسوس ناک معاشرتی
صورت حال کا آئینہ دار ہے.اس کے ذریعہ ہم اسلام کے انداز فکر اور جدید معاشرہ
کی سوچ کے مابین موازنہ کر سکتے ہیں.صرف بے فکرے طلباء کی مجالس ہی نہیں بلکہ
بڑے سنجیدہ مزاج اور معزز لوگوں کا بھی یہ وطیرہ ہے کہ وہ تمسخر کے ساتھ اس اسلامی
حکم کے متعلق اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کیا کرتے ہیں اور اسے کوئی غیر شائستہ اور
دل آزار بات نہیں سمجھتے.کچھ ہی عرصہ پہلے کی بات ہے کہ مجھے فرینکفورٹ کے ایک
سینئر جج صاحب کا ایک خط موصول ہوا.میں انہیں ذاتی طور پر جانتا ہوں.بہت
دانا، کھلے ذہن کے مالک، شائستہ اور اہم آدمی ہیں.انہوں نے اپنے خط میں اسلام
میں تعدد ازدواج کی محدود اجازت پر اعتراض کیا اور وہ بھی اپنی بات کو ایک
بھونڈے مذاق کے ذریعہ واضح کرنے کی خواہش کو دبا نہیں سکے.یا ممکن ہے یہ محض
میرا تاثر ہو.بہر حال ایک لمحہ کے لئے مجھے خیال آیا کہ میں بھی ان کے مذاق کا
جواب Forefathers والے لطیفہ کے ساتھ دوں لیکن الحمد للہ کہ مجھے صحیح فیصلہ کی
توفیق ملی اور میں نے ایسا نہیں کیا.جو مختصر جواب میں نے انہیں ارسال کیا وہ یہ تھا
کہ اول تو اسلام میں ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کی یہ اجازت عام نہیں ہے بلکہ
بعض مخصوص حالات سے تعلق رکھتی ہے جب معاشرہ کی صحت اور عورتوں کے حقوق
ہر دو کی حفاظت کے لئے اس اجازت کا استعمال ضروری ہو جائے.دوم یہ کہ
قرآن کریم ایک معقولی اور منطقی کتاب ہے.یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ مسلمانوں کو کسی ایسی
بات پر عمل کرنے کی ہدایت کرے جس پر عمل ناممکن ہو.اللہ تعالیٰ نے مردوں اور
عورتوں کو کم و بیش مساوی تعداد میں پیدا کیا ہے.پس کیسے ممکن ہے کہ اسلام جیسا
معقول مذہب جو بار بار اس امر پر زور دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قول اور اس کے فعل
113
Page 126
میں کوئی تضاد نہیں ہے ایک ایسی تعلیم دے جو واضح طور پر غیر فطری اور غیر حقیقی ہو.ایک ایسی تعلیم جس پر اگر عمل کی کوشش کی جائے تو توازن خطرناک حد تک بگڑ جائے
گا اور ایسی مشکلات اور مایوسیاں پیدا ہوں گی جنکا کوئی حل نہیں ہوگا.ایک ایسے
چھوٹے سے ملک کا تصور کریں جس میں شادی کے قابل مردوں کی تعداد دس لاکھ
ہے اور کم و بیش اتنی ہی عورتیں ہیں جو شادی کے قابل ہیں.اگر تعدد ازدواج کی اس
اجازت کو ایسا حکم سمجھا جائے جس پر حرف بحرف عمل کرنا ضروری ہو تو صرف دو لاکھ
پچاس ہزار مرد دس لاکھ عورتوں سے شادی کر لیں گے اور سات لاکھ پچاس ہزار مرد
بن بیا ہے رہ جائیں گے.حالانکہ دنیا کے سب مذاہب سے زیادہ اسلام تمام مردوں
اور عورتوں پر زور دیتا ہے کہ وہ شادی کریں.قرآن کریم کے نزدیک میاں بیوی کا
تعلق محبت کے فطری جذبہ پر مبنی ہوتا ہے اور دونوں کے لئے تسکین اور طمانیت کا
سامان مہیا کرتا ہے.فرمایا:
وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ الْمُؤْمِتِ وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا
ہو وہ وس و وہ وہ وہ
اتيتموهن أجورهن محصِنِينَ غَيْر مسفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَان
(سورۃ المائدہ آیت ۶)
ترجمہ.اور پاکباز مومن عورتیں اور ان لوگوں میں سے پاکباز عورتیں
بھی جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تمہارے لئے حلال ہیں جبکہ تم انہیں
نکاح میں لاتے ہوئے ان کے حق مہر ادا کرو نہ کہ بدکاری کے مرتکب
بنتے ہوئے اور نہ ہی پوشیدہ دوست بناتے ہوئے.اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم تجرد کی زندگی بسر کرنے کے نظریہ کو رد کرتا ہے
اور اسے انسانوں کا خود ساختہ دستور یا رواج قرار دیتا ہے (مثال کے طور
ملاحظہ ہو سورۃ الحدید آیت (۲۸) دنیا سے اپنے آپ کو الگ تھلگ کر لینے سے کچھ بھی
114
Page 127
تو حاصل نہیں ہو سکتا.نہ ہی فطری خواہشات کا انکار کر کے خود کو سزا دینے کا کوئی مفید
-Ch
نتیجہ نکل سکتا ہے.در حقیقت اسلام کا ازدواجی نظام بہت مضبوط بنیادوں پر استوار کیا گیا ہے.وقت کی کمی کے باعث یہ ممکن نہیں کہ اصل موضوع سے ہٹ کر ان امور پر بات کی
جائے کہ جیون ساتھی کے انتخاب سے متعلق اسلامی تقاضے کیا ہیں اور دیگر متعلقہ امور
مثلاً طلاق کے قواعد وضوابط کیا ہیں اور ایسے مسائل کا اسلام کیا حل تجویز کرتا ہے؟
اب ہم تعدد ازدواج کے مضمون کی طرف واپس آتے ہیں.قرآن کریم کے
مطالعہ سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ تعدد ازدواج سے متعلق آیات کے پس منظر
میں زمانہ جنگ کے بعد کے مخصوص حالات کا ذکر ہو رہا ہے.جنگ کے بعد بہت سے
یتیم بچے اور جوان بیوائیں باقی رہ جاتی ہیں.مردوں اور عورتوں کی آبادی کا
تناسب بگڑ جاتا ہے.دوسری جنگ عظیم کے بعد جرمنی بھی ایک ایسی ہی صورت حال
سے دوچار تھا جس کے نتیجہ میں پیدا ہونے والی مشکلات کا کوئی حل نظر نہیں آتا.زندگی بھر ایک وقت میں ایک ہی شادی کرنے کی عیسائیت کی سخت تعلیم اس مسئلہ کا
حل پیش کرنے سے قاصر تھی.جرمنی میں چونکہ اسلام غالب اکثریت کا مذہب نہیں تھا
اس لئے وہاں کے باشندوں کو آبادی کے اس عدم تناسب کے بد نتائج بھگتنے پڑے.بہت بڑی تعداد میں کنواری لڑکیاں اور جوان بیوہ عورتیں ایسی تھیں کہ مایوسیاں جن کا
مقدر بن گئیں.شادی ان کے لئے ایک ایسا خواب بن کر رہ گئی جس کی تعبیر ڈھونڈنے
سے بھی نہیں ملتی تھی.براعظم یورپ میں اتنے وسیع پیمانے پر صرف جرمنی ہی ان
خطر ناک معاشرتی مسائل سے دوچار نہیں ہوا بلکہ جنگ کے بعد آنے والا اخلاقی تنزل
اور جنسی بے راہ روی کا سیلاب سارے مغربی معاشرے کو بہا کر لے گیا.ان برائیوں
کے پھیلنے کی وجہ مردوں اور عورتوں کی آبادی کا عدم تناسب بھی تھا.115
Page 128
ہر غیر متعصب شخص بآسانی سمجھ سکتا ہے کہ ایسے تمام مسائل کا حل یہی ہے کہ
مردوں کو ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کی اجازت دی جائے.یہ حل مردوں کی
جنسی خواہشات کی تسکین کی خاطر تجویز نہیں کیا گیا ہے بلکہ عورتوں کی ایک بڑی تعداد
کے فطری انسانی تقاضوں کو پورا کرنا ہی اس کا اصل مقصد ہے.اگر اس انتہائی معقول
اور حقیقت پسندانہ حل کو مسترد کر دیا جائے تو پھر معاشرہ کیلئے یہی ایک متبادل راستہ رہ
جاتا ہے کہ وہ تیزی سے بگاڑ اور بے راہ روی کا شکار ہو جائے اور قعر مذلت میں گرتا
چلا جائے.افسوس صد افسوس کہ مغرب یہی راستہ اختیار کر چکا ہے..اگر آپ زیادہ حقیقت پسندی سے اور غیر جذباتی ہو کر ایک بار پھر ان دو
راستوں کا جائزہ لیں تو یقیناً یہ حقیقت کھل کر سامنے آجائے گی کہ تعدد ازدواج
مردوزن میں مساوات کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ تو ایک بھاری ذمہ داری اٹھانے یا نہ
اٹھانے کا سوال ہے.یاد رہے کہ اسلام ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کی اجازت
صرف اس شرط پر دیتا ہے کہ مرد پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ مشکل چیلنج قبول کرے
کہ وہ دوسری تیسری یا چوتھی بیوی کے ساتھ پورے انصاف سے کام لے گا اور
مساوی سلوک کرے گا.قرآن کریم اس کے متعلق فرماتا ہے.- واس
10-
وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتمى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى
وَتُلْكَ وَ رُبع = فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى
( سورة النساء آیت ۴)
أَلَّا تَعُولُوا
ترجمہ.اور اگر تم ڈرو کہ تم یتامیٰ کے بارہ میں انصاف نہیں کر سکو گے تو
عورتوں میں سے جو تمہیں پسند آ ئیں ان سے نکاح کرو.دو دو اور تین
تین اور چار چار.لیکن اگر تمہیں خوف ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو
پھر صرف ایک (کافی ہے ) یا وہ جن کے تمہارے داہنے ہاتھ مالک
ہوئے.یہ ( طریق) قریب تر ہے کہ تم نا انصافی سے بچو.116
Page 129
تعدد ازدواج کے مقابل پر ایک ہی متبادل راستہ رہ جاتا ہے جو اتنا مکروہ اور
بدصورت ہے کہ اس کے تصور ہی سے رونگٹے کھڑے ہونے لگتے ہیں.ایک ایسے
معاشرہ میں جس پر مذہب کا گہرا اثر نہ ہو وہاں تو صورت حال اور بھی گھمبیر ہو جاتی
ہے.غیر شادی شدہ عورتوں کی ایک بہت بڑی تعداد کو آپ کس منہ سے مورد الزام
ٹھہرا سکیں گے جب وہ مردوں کو اپنی جانب مائل کرنے کی کوشش کریں گی.عورتیں
بھی آخر انسان ہیں.ان کے بھی جذبات ہیں.ان کی بھی خواہشات ہیں جو تشنہ رہ
گئی ہیں.خصوصاً جنگ کے نتیجہ میں ہونے والے گہرے نفسیاتی اور جذباتی صدمات
کی وجہ سے کسی شریک حیات کے سہارے کی ضرورت تو اور بھی بڑھ جاتی ہے.ان
حالات میں شادی سے ملنے والے گھر اور تحفظ کے بغیر زندگی بالکل ویران ہو کر رہ
جاتی ہے.زندگی کا کوئی ساتھی نہ ہو اور نہ ہی اولاد کی کوئی توقع ہو تو ایسے لوگوں کا
مستقبل بھی ان کے حال کی طرح ایک تاریک خلا بن کر رہ جاتا ہے.اگر تنہائی کی ماری ہوئی ایسی عورتیں کسی قدر قربانی کر کے اور کچھ لو کچھ دو“ کے
اصول پر چلتے ہوئے جائز اور قانونی طور پر گھر نہیں بسا سکتیں اور معاشرتی نظام کا حصہ
نہیں بن سکتیں تو یہ صورت حال بھی معاشرہ کے امن کے لئے بے حد تباہ کن ثابت
ہوگی.ایسی عورتیں کسی نہ کسی طریقہ سے شادی شدہ عورتوں کے خاوندوں کے ساتھ
ناجائز تعلقات قائم کریں گی اور اس کا نتیجہ لازماً بہت برا ہوگا.شادی شدہ عورتوں
کا اپنے خاوندوں پر سے اعتبار اٹھ جائے گا.شکوک وشبہات جنم لیں گے.میاں اور
بیوی کے باہمی اعتماد میں کمی سے کئی گھروں کی بنیادیں متزلزل ہو جائیں گی.بے
وفا مرد جب ایک احساس جرم کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو اس سے مزید نفسیاتی
پیچیدگیاں پیدا ہونگی اور جرائم کا رجحان بڑھے گا.سب سے بڑھ کر یہ کہ محبت اور
وفا کے آبگینے چکنا چور ہو جائیں گے.پیار کی رعنائیاں مٹ جائیں گی.سچے جذبے
117
Page 130
مفقود ہو جائیں گے اور سفلی جذبات کے وقتی ابال باقی رہ جائیں گے.جو لوگ زندگی کے ہر شعبہ میں مرد اور عورت کے درمیان مساوات کی بات کرتے
ہیں وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ جہاں مرد اور عورت خلقی طور پر مختلف ہیں وہاں ان میں
مساوات کا سوال ہی بے معنی ہے.مثلاً بچے پیدا کرنے کا کام صرف عورت ہی کر سکتی
ہے.نو ماہ سے زائد عرصہ تک نسل انسانی کے بیج کو صرف عورت ہی اپنے پیٹ میں رکھ
کر اس کی پرورش کر سکتی ہے.عورت ہی ہے جو شیر خوارگی اور بچپن کے ابتدائی دور
میں اپنے بچوں کی دیکھ بھال کا فریضہ سرانجام دے سکتی ہے جبکہ کوئی مرد یہ کام نہیں کر
سکتا.یہ عورتیں ہی ہیں جو انتہائی قریبی خونی رشتہ ہونے کی وجہ سے اپنے بچوں کے
ساتھ مردوں کی نسبت کہیں زیادہ گہرا اور مضبوط نفسیاتی تعلق استوار کرتی ہیں.اگر کوئی معاشرتی اور اقتصادی نظام عورت اور مرد کے درمیان اس خلقی فرق کو
مدنظر نہیں رکھتا اور اس فرق کے باعث معاشرہ میں عورت اور مرد کے اپنے اپنے
مخصوص کردار کو نظر انداز کرتا ہے تو ایسا نظام ایک صحتمند سماجی اور اقتصادی توازن کے
پیدا کرنے میں لازماً نا کام ہو جائے گا.عورت اور مرد کی جسمانی ساخت میں فرق ہی
وہ بنیاد ہے جس کے نتیجہ میں اسلام نے دونوں کے لئے ان کے مناسب حال الگ
الگ دائرہ کار مقرر کئے ہیں.اسلام کے معاشرتی نظام کے مطابق عورت کو خاندان
کے لئے روزی کمانے کی ذمہ داری سے جہاں تک ممکن ہے آزاد رکھا جانا چاہئے.اصولی طور پر یہ ذمہ داری مردوں پر عائد ہوتی ہے لیکن اگر عورتوں کو اپنی گھریلو
ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہونے کے بعد فراغت ہو تو کوئی وجہ نہیں کہ انہیں اقتصادی
ترقی کے عمل میں حصہ لینے سے روکا جائے.شرط صرف یہی ہے کہ ان کے اصل
فرائض نظر انداز نہ ہوں.اسلام کی یہی تعلیم ہے.پھر ہم دیکھتے ہیں کہ عورتیں بالعموم جسمانی ساخت کے لحاظ سے مردوں کی نسبت
118
Page 131
کمزور ہوتی ہیں.اللہ تعالی نے حیرت انگیز طور پر عورتوں کو بعض لحاظ سے بہت
مضبوط قومی بھی عطا فرمائے ہیں.اس کی وجہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ انکے خلیوں میں
نصف کروموسوم زائد ہوتا ہے.یہی وہ نصف کروموسوم ہے جو کہ مردوں اور عورتوں
کے درمیان پائے جانے والے فرق کا ذمہ دار ہے.اور یہ انہیں اسی لئے دیا گیا ہے
کہ وہ اس عظیم ذمہ داری کو اٹھا سکیں جو حمل، زچگی اور ایام رضاعت میں انہیں ادا
کرنی ہوتی ہے.اس صلاحیت کے باوجود عورت بظاہر جسمانی لحاظ سے مضبوط اور
سخت جان نہیں ہوتی.پس مساوات کے نام پر یا کسی اور بہانہ سے عورتوں پر معیشت
کے وہ کام مسلط نہیں کرنے چاہئیں جن میں مردانہ جفاکشی اور مشقت کی ضرورت
ہوتی ہے.عورت کی نزاکت اس امر کی بھی متقاضی ہے کہ اس کے ساتھ زیادہ نرمی
اور رافت کا سلوک روا رکھا جائے.روزمرہ کی زندگی میں عورتوں کو ہرگز مجبور نہیں
کرنا چاہئے کہ وہ مردوں کے برابر بوجھ اٹھا ئیں بلکہ ان کا بوجھ مردوں کی نسبت ہلکا
ہونا چاہئے.مذکورہ بالا بحث سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر خانہ داری کی مخصوص ذمہ داری عورت
یا مرد میں سے کسی ایک کے سپرد کرنے کا سوال ہو تو یقیناً عورت مرد کے مقابلہ میں
اس کی کہیں زیادہ اہل ہے.مزید برآں فطری طور پر بھی عورت پر بچوں کی نگہداشت
کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے.یہ ایسی ذمہ داریاں ہیں جن میں مرد محض جزوی طور پر
ہی عورت کے ساتھ شریک ہوسکتا ہے.عورتوں کو یہ حق ملنا چاہئے کہ وہ مردوں کے مقابلہ میں اپنا زیادہ تر وقت گھروں
میں گزار سکیں.لیکن جب انہیں روزی کمانے کی ذمہ داری سے آزاد رکھا جاتا ہے تو
انہیں چاہئے کہ وہ لازماً اپنے فارغ وقت کو اپنی اور معاشرہ کی فلاح و بہبود کیلئے خرچ
کریں.عورتوں کے متعلق اسلام کی تعلیم یہی ہے.اسی وجہ سے یہ تصور پیدا ہوتا ہے
119
Page 132
کہ عورت کا اصل مقام اس کا گھر ہے.اس سے ہرگز یہ مراد نہیں ہے کہ عورتیں ہمیشہ
باورچی خانہ یا گھر کی چاردیواری کے اندر ہی قید رہیں.اسلام کسی بھی طرح عورتوں
کو اس حق سے محروم نہیں کرتا کہ وہ اپنے فارغ اوقات میں کسی کام کی انجام دہی کے
لئے گھروں سے باہر جائیں یا وہ اپنی پسند کے کسی صحت مند شغل میں حصہ لیں مگر شرط
صرف یہ ہے کہ عورتوں کی ان سرگرمیوں کی وجہ سے ان کے اصل فرائض کی ادائیگی
یعنی آئندہ نسل کی نگہداشت متاثر نہ ہو.اور ان کی یہ زائد مصروفیات مستقبل کی
نسلوں کے مفاد کے تحفظ اور ان کے حقوق کی ادائیگی میں حارج نہ ہوں.چنانچہ دیگر
وجوہات کے علاوہ اس وجہ سے بھی اسلام عورتوں کی حد سے زیادہ سماجی سرگرمیوں
میں شمولیت اور مردوں کے ساتھ آزادانہ میل جول کی سختی کے ساتھ حوصلہ شکنی کرتا
ہے.اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ عورت کی سرگرمیوں کا اصل مرکز اس کا گھر ہونا
چاہئے.دور جدید کی بہت سی برائیوں کا یہ ایک بہت دانشمندانہ اور عملی حل ہے.اگر
گھر عورت کی دلچسپی کا مرکز نہ رہے تو بچے نظر انداز ہو جاتے ہیں اور گھریلو زندگی تباہ
و برباد ہو جاتی ہے.ایک ایسے گھر کی تعمیر جہاں ماں کو مرکزی حیثیت حاصل ہو دیگر خونی رشتوں کی
مضبوطی کا تقاضا کرتی ہے.اس کے لئے اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کے ساتھ
ایک سچا اور پر خلوص تعلق قائم کرنا ضروری ہو جاتا ہے.اگر چہ ہر فیملی یونٹ الگ
الگ رہ سکتا ہے لیکن اسلام ایک وسیع تر خاندان کے تصور کو قائم کرتا ہے اور اسے
فروغ دیتا ہے.اس کی کئی وجوہات ہیں جن میں سے بعض درج ذیل ہیں.(۱) وسیع تر خاندان کا تصور معاشرتی عدم توازن کو روکتا ہے.(۲) ماں باپ، بیٹے بیٹیوں اور بہن بھائیوں وغیرہ کے درمیان محبت کا مضبوط
رشتہ ایک صحت مند گھر کی حفاظت کرتا ہے.گھر کے افراد کا یہ طبعی قرب دادا دادی،
120
Page 133
نانانانی ، چاچی، پھوپھا پھوپھی، بھانجوں بھتیجوں، رشتے کے بھائی بہنوں اور پوتے
پوتیوں وغیرہ کے ساتھ ایک پرخلوص سچے اور قریبی تعلق کی وجہ سے مزید مضبوط
ہو جائے گا.یہ شعور کہ ہم کسی کے ہیں اور کوئی ہمارا ہے محبت اور مسرت کے نئے نئے راستے
دریافت کرتا رہتا ہے اور یوں ایک وسیع تر خاندانی نظام قائم ہوتا چلا جاتا ہے.(۳) اس قسم کے وسیع خاندانی نظام سے وابستہ گھروں کے ٹوٹنے اور بکھر نے کا
امکان کم ہو جاتا ہے.آج کے معاشرہ میں عموما لوگ محض گھر کے نام پر ایک چھت
کے نیچے رہ کر زندگی کے دن پورے کر رہے ہیں.لیکن اگر محبت و الفت کے وسیع
تعلقات قائم ہو جائیں تو یہ منظر بدل جاتا ہے.خاندان کے بزرگوں کو ایک مرکزی
حیثیت حاصل ہوتی ہے.ان کی ذات خاندان کی اکثر سرگرمیوں کا محور بن جاتی
ہے.وہ ایک شمع کی مانند ہوتے ہیں جنکی طرف سب پروانہ وار کھنچے چلے آتے ہیں.پیار اور محبت کے یہ گہرے رشتے زندہ رہیں تو تنہائیوں کے مارے ہوئے ایسے
شکستہ حال لوگ پیدا نہیں ہوتے جنہیں لوگ فراموش کر چکے ہوں اور معاشرہ میں ان
کا کوئی مقام باقی نہ رہا ہو یہاں تک کہ خود ان کے گھر والوں نے انہیں بے کار اور نکما
جان کر ان سے قطع تعلق کر لیا ہو.خاندان اور گھر کے متعلق اسلام کا تصور بعینہ یہی ہے.اسلامی نظریہ کے مطابق
گھر معاشرتی زندگی کی سب سے اہم اور بنیادی اکائی ہے.اس کے برعکس عصر حاضر
کے جدید معاشروں میں بہت سے بوڑھے یا معذور ماں باپ کو بوجھ سمجھ کر پھینک دیا
جاتا ہے.اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ عصر جدید میں گھر اور خاندان کا تصور اسلام
کے دیئے ہوئے تصور سے بہت مختلف ہے.121
Page 134
عمر رسیدہ افراد کی دیکھ بھال
موجودہ دور میں معاشرہ کے عمر رسیدہ افراد کی دیکھ بھال کی ذمہ داری رفتہ رفتہ
حکومت کے سر پر ڈالی جا رہی ہے.بوڑھوں کی نگہداشت پر اٹھنے والے اخراجات کو
قومی معیشت پر ایک بوجھ قرار دیا جاتا ہے.حقیقت یہ ہے کہ حکومت ان لوگوں پر جتنا
بھی خرچ کرنے پر آمادہ ہو وہ انہیں حقیقی اطمینان اور سکون مہیا نہیں کر سکتی.ان کا
دکھ تو یہ ہے کہ ان کے اپنے پیارے انہیں قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں.وہ
زندگی کے لق و دق صحرا میں بے یار و مددگار چھوڑ دیئے گئے ہیں.تنہائی کا بڑھتا ہوا
کرب انہیں اندر ہی اندر کھائے جا رہا ہے.یہ دکھ ایسے ہیں جن کا مداوا اکثر لوگوں
کے بس کی بات ہی نہیں.جب نزد یکی رشتہ دار ان ضعیف لوگوں کو بھول جائیں تو یہ
بالکل ناممکن ہے کہ دور کے رشتہ دار مدد کے لئے آگے آئیں گے.ایسے معاشروں
میں بوڑھے لوگوں کے لئے الگ گھروں کی ضرورت رفتہ رفتہ بڑھتی ہی چلی جا رہی
ہے اور حکومت کے لئے ہمیشہ یہ ممکن نہیں ہوتا کہ وہ اپنے بجٹ میں ان کے لئے اتنی
رقم مختص کر سکے جس سے ایک شریفانہ زندگی کی کم سے کم ضروریات ہی پوری کی
جاسکیں.دوسرے یہ کہ ان کے اصل دکھ جسمانی نہیں بلکہ نفسیاتی ہیں.جسمانی عوارض کا علاج گہرے نفسیاتی مسائل کی نسبت بہت آسان ہوتا ہے اور یہی
نفسیاتی دکھ اور روحانی کرب ہیں جن میں آج بہت بڑی تعداد میں عمر رسیدہ لوگ مبتلا
ہیں.مسلم اکثریت رکھنے والے ممالک میں بھی اگر چہ اخلاقی اقدار زوال پذیر ہیں مگر
جو صورت حال آج باقی دنیا میں در پیش ہے وہ نا قابل تصور ہے.مسلمان ممالک میں
آج بھی عمر رسیدہ لوگوں کے ساتھ ایسی بے رحمی اور بے عزتی کا سلوک روا رکھنا ایک
122
Page 135
قابل شرم اور باعث ذلت بات سمجھی جاتی ہے.اکثر مسلمانوں کے نزدیک یہ ایک
شرمناک بات ہے کہ اپنے بوڑھے رشتہ داروں کی ذمہ داری حکومت وقت پر ڈال دی
جائے خواہ حکومت ان کی دیکھ بھال کرنے کے لئے بخوشی تیار بھی ہو.اس اعتبار سے ایک مسلمان عورت کا خانگی اور گھر یلو کردار بچوں کے بالغ ہو
جانے کے بعد ختم نہیں ہو جاتا.اپنے خاندان کے ماضی سے ایک دائمی تعلق کے
ساتھ ساتھ وہ مستقبل کے ساتھ بھی اپنا گہرا رشتہ استوار رکھتی ہے.یہ عورت کا جذبہ
شفقت و رحم اور ضرورت مندوں کا خیال رکھنے کی فطری صلاحیت ہی ہے جو معاشرہ
کے معمر افراد کے لئے سہارا بن جاتی ہے.عورت کی توجہ سے ہی بوڑھے لوگوں کو
پہلے جیسی قدر و منزلت اور پہلے جیسا احترام حاصل رہتا ہے اور وہ اپنے بڑھاپے میں
بھی خاندان کا ایک لازمی جزو سمجھے جاتے ہیں.ماں ان بزرگوں کی دیکھ بھال میں
بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے.وہ ان کے پاس بیٹھتی ہے تا کہ انہیں تنہائی کا احساس نہ
ہو.اس فرض کو وہ ایک مشقت اور چٹی نہیں بجھتی بلکہ اس میں انسانی رشتوں کا ایک
طبعی زندہ اور پر جوش اظہار پایا جاتا ہے.اور پھر وقت آنے پر وہ خود اس یقین کے
ساتھ بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھتی ہے کہ معاشرہ اسے کبھی نہیں دھتکارے گا.وہ یہ
اطمینان رکھتی ہے کہ اسے گئے وقت کی بے مصرف نشانی سمجھ کر بے آسرا نہیں چھوڑ دیا
جائے گا.بلاشبہ اکاڈ کا استثنائی مثالیں تو ہر معاشرہ میں نظر آتی ہیں.ایسے مسلمان
معاشروں میں والدین کو بے سہارا چھوڑ دینے کے واقعات شاذ کے زمرے میں
آتے ہیں اور دیگر معاشروں کے برعکس بوڑھوں کے الگ گھر بھی نسبتاً بہت کم تعداد
میں دکھائی دیتے ہیں.یہاں مجھے ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے جسے سن کر شاید بعض لوگ تو ہنس پڑیں لیکن ممکن
ہے کچھ لوگوں کو یہ لطیفہ رُلا بھی دے.ہوا یوں کہ ایک بچے کو یہ دیکھ کر کہ اس کا باپ
123
Page 136
اس کے بوڑھے دادا کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا تھا بہت دکھ محسوس ہوتا تھا.دادا
کے ساتھ یہ بدسلوکی روز بروز بڑھتی جا رہی تھی.آہستہ آہستہ اسے ایک اچھے اور
آرام دہ سونے کے کمرہ سے نکال کر ایک تنگ اور غیر آرام دہ کمرہ میں منتقل کر دیا
گیا.ایک مرتبہ غیر معمولی طور پر شدید سردی پڑی تو بوڑھے دادا نے شکایت کی کہ
میرا کمرہ بہت ہی سرد ہے اور لحاف اتنا ہلکا ہے کہ رات بھر سردی سے ٹھٹھرتا رہتا ہوں
اور آرام سے سو نہیں سکتا.بچے کا باپ یہ سن کر پھٹے پرانے بے کار پڑے ہوئے
کپڑوں میں سے کوئی فالتو کمبل تلاش کرنے لگا.یہ منظر دیکھ کر بچے نے اپنے باپ
سے کہا کہ ابا یہ سارے ہی پھٹے پرانے کپڑے دادا کو نہ دیں، کچھ ان میں سے میرے
لئے بھی رہنے دیں تا کہ جب آپ بوڑھے ہو جائیں تو میں یہ کپڑے آپ کو دے
سکوں.بچے کے اس معصومانہ اظہار ناراضگی میں آج کے عمر رسیدہ لوگوں کے
سارے دکھ سمائے ہوئے ہیں.جہاں ایک مسلمان معاشرہ میں عمر رسیدہ بزرگوں کے ساتھ بدسلوکی کی مثالیں
ستثنا کا حکم رکھتی ہیں وہاں جدید معاشروں میں بوڑھوں کے ساتھ ان کے عزیزوں کی
طرف سے حسن سلوک کی مثالیں بھی شاذ کی حیثیت رکھتی ہیں اور تعداد میں گھٹتی چلی
جارہی ہیں.قرآن کریم نے تو مسلمانوں کو یہ تعلیم دی ہے کہ :
وَقَضَى رَبُّكَ إِلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَا لِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ
ވ ވ ސ
دوره
أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلاَ تَقُلْ لَّهُمَا رُوِ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا
سکس
وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّينِي صَغِيرًا
(سورۃ بنی اسرائیل آیات ۲۵،۲۴)
ترجمہ.اور تیرے رب نے فیصلہ صادر کر دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی
عبادت نہ کرو اور والدین سے احسان کا سلوک کرو.اگر ان دونوں میں
سے کوئی ایک تیرے پاس بڑھاپے کی عمر کو پہنچے یا وہ دونوں ہی ، تو انہیں
124
Page 137
اُف تک نہ کہہ اور انہیں ڈانٹ نہیں اور انہیں نرمی اور عزت کے ساتھ
مخاطب کر.اور ان دونوں کے لئے رحم سے عجز کا پر جھکا دے اور کہہ کہ
اے میرے ربّ! ان دونوں پر رحم کر جس طرح ان دونوں نے بچپن
میں میری تربیت کی.زیر بحث موضوع پر ان آیات کی اہمیت واضح ہے.ان میں یہ تعلیم دی گئی ہے
که بنی نوع انسان کو چاہئے کہ توحید باری تعالیٰ کے بعد اپنے عمر رسیدہ والدین سے
پیار اور محبت اور حسنِ سلوک کو باقی سب امور پر ترجیح دیا کریں.یہ بزرگ اپنی عمر
کے ایک مشکل دور میں سے گزر رہے ہیں.اس عمر میں بعض اوقات ان کا رویہ بڑا
صبر آزما اور ناگوار ہوسکتا ہے.ایسی صورت میں یہ آیات ہمیں حکم دیتی ہیں کہ ان
کے خلاف معمولی سا اظہار نفرت بھی نہیں ہونا چاہئے اور نہ ہی نا پسندیدگی کا کوئی کلمہ
منہ سے نکلنا چاہئے.والدین کی ان ناگوار باتوں کے باوجود ان کے ساتھ انتہائی
عزت و احترام سے پیش آنا چاہئے.آنے والی نسلوں کا جانے والی نسل کے ساتھ ادب و احترام کا ایک زندہ اور
مضبوط تعلق ہونا چاہئے.اس پر زور بھی اسی لئے دیا گیا ہے تا کہ دونوں نسلوں کے
درمیان کسی قسم کا بُعد پیدا نہ ہونے پائے ورنہ پرانی نسل جن اعلیٰ اخلاقی اقدار پر قائم
تھی وہ نئی نسل میں کبھی بھی پوری طرح منتقل نہیں ہوسکتیں.اس لئے اسلام کی
معاشرتی تعلیم اور اس کا فلسفہ یہ ہے کہ کوئی نسل بھی اپنے سے پہلی اور بعد میں آنے
والی نسل کے مابین کسی قسم کا فاصلہ پیدا نہ ہونے دے.گویا اسلامی تعلیم کے مطابق
جریشن گیپ (Generation Gap) کی ہرگز کوئی گنجائش نہیں.ہے.جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے اسلام میں خاندان کا تصور صرف ایک گھر کے
افراد تک محدود نہیں ہے.درج ذیل آیت میں مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ وہ نہ
125
Page 138
صرف اپنے والدین پر خرچ کریں بلکہ ان عزیزوں اور رشتہ داروں پر بھی خرچ کریں
جو والدین کے بعد زیادہ قریبی ہیں.یہ خرچ اس رنگ میں ہونا چاہئے جس سے ان
کی عزت نفس مجروح نہ ہو بلکہ باہمی پیار اور محبت میں اضافہ ہو.11-0-
وَاعْبُدُوا اللهَ وَلَا تُشْرَكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَمَى
وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ
السبيل « وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا
(سورۃ النساء آیت ۳۷)
ترجمہ.اور اللہ کی عبادت کرو اور کسی چیز کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ اور
والدین کے ساتھ احسان کرو اور قریبی رشتہ داروں سے بھی اور یتیموں
سے بھی اور مسکین لوگوں سے بھی اور رشتہ دار ہمسایوں سے بھی اور
غیر رشتہ دار ہمسایوں سے بھی اور اپنے ہم جلیسوں سے بھی اور مسافروں
سے بھی اور ان سے بھی جن کے تمہارے داہنے ہاتھ مالک ہوئے.یقیناً
اللہ اس کو پسند نہیں کرتا جو متکبر (اور ) شیخی بگھارنے والا ہو.اس آیت سے ظاہر ہے کہ قرآن کریم والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کرتا
ہے.اگر عصر حاضر کا معاشرہ قرآن کریم کی اس تعلیم سے نصیحت حاصل کرلے تو آج
کے بہت سے مسائل جو در حقیقت ترقی یافتہ معاشرہ کے چہرہ پر بدنما داغ سے کم نہیں
ختم ہو جائیں گے.عمر رسیدہ لوگوں کے لئے الگ گھروں کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی
سوائے چند ایسے بدقسمت بوڑھوں کے جن کی دیکھ بھال کرنے والے ان کے کوئی
قریبی رشتہ دار موجود نہ ہوں.اسلامی معاشرہ میں والدین اور بچوں کے درمیان
باہمی محبت کے تعلق پر اس قدر اور بار بار زور دیا گیا ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ بچے
اپنے والدین کو بڑھاپے میں اپنے عیش وعشرت کی خاطر بے سہارا چھوڑ دیں.126
Page 139
مستقبل کی نسلیں
جہاں تک مستقبل کی نسلوں کا تعلق ہے اس بارہ میں اسلام نے ایک منفرد انداز
میں معاشرہ کی رہنمائی اور تربیت کا اہتمام کیا ہے.اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ والدین
اور بچوں کے درمیان بہترین تعلق کے لئے میاں بیوی کے مابین پیار اور محبت کا ایک
مثالی تعلق ہونا بے حد ضروری ہے.اس لحاظ سے سورۃ النساء کی آیت نمبر ۳۵ جس
میں مرد کے قوام یعنی سر پرست ہونے کا ذکر ہے خاوند پر بہت بھاری ذمہ داری عائد
کرتی ہے.اگر خاوند کا طرز عمل خوشگوار گھریلو زندگی کے فروغ کے لئے سازگار نہیں
اور مناسب ماحول پیدا نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایسا خاوند بحیثیت نگران
اور سر پرست اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے میں ناکام رہا ہے.یہ بات یاد رکھنی چاہئے
کہ قوام کی بہترین مثال ہمارے پیارے آقا و مولیٰ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کی ذات والا صفات ہے.آپ اپنے اہل بیت کے ساتھ کسی قسم کی کوئی سختی روا نہیں
رکھتے تھے.آپ کا انداز نہ تو تحکمانہ تھا اور نہ ہی آپ ان لوگوں کی طرح تھے جو
ہمیشہ اپنی ہی بات منواتے ہیں.آپ کی محبوب شخصیت میں کوئی ایسا تکلف یا ترشی کا
شائبہ تک نہیں تھا جس سے لوگوں کی طبائع میں کوئی نفور پیدا ہو.اہل بیت کی تربیت
ایک عظیم الشان ذمہ داری تھی اور یہ ذمہ داری آپ نے اس شاندار طریق پر ادا کی
جو آنے والے سب زمانوں کے لئے ایک نہایت اعلیٰ زندہ و تابندہ اور
قابل تقلید مثال ہے.ان سب لوگوں کو جو لفظ قوام کے حقیقی معنی جاننا اور سمجھنا چاہتے
ہیں آنحضرت ﷺ کے اس نمونہ پر غور کرنا چاہئے.ایک مشہور حدیث میں جو
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے آنحضرت ﷺ نے فرمایا:
مومنوں میں ایمان کے لحاظ سے کامل ترین مومن وہ ہے جس کے
اخلاق اچھے ہیں اور تم میں سے اخلاق کے لحاظ سے بہترین وہ ہے جو
127
Page 140
اپنی بیویوں سے بہترین سلوک کرتا ہے“.(ترمذی)
اگر والدین اس بات کے متمنی ہیں کہ ان کے بچے بڑے ہو کر ایک صالح معاشرہ
کے افراد بنیں تو انہیں یاد رکھنا چاہئے کہ میاں بیوی کے باہمی تعلقات بچوں کے کردار
کوسنوارنے یا بگاڑنے میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں.قرآن کریم فرماتا ہے:
وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الرُّوْرَه وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًاO وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا
ده
بِايَتِ رَبِّهِم لَم يَخِرُوا عَلَيْهَا صَمَّا وَعَميَانًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ
اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًاO (سورة الفرقان آیات ۷۳ تا ۷۵ )
ترجمہ.اور وہ لوگ جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب وہ لغویات کے
پاس سے گزرتے ہیں تو وقار کے ساتھ گزرتے ہیں.اور وہ لوگ کہ
جب انہیں ان کے رب کی آیات یاد کروائی جاتی ہیں تو ان پر وہ بہرے
اور اندھے ہو کر نہیں گرتے.اور وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے
ربّ! ہمیں اپنے جیون ساتھیوں اور اپنی اولا د سے آنکھوں کی ٹھنڈک
عطا کر اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے.ان آیات میں جو دعا سکھائی گئی ہے وہ اپنے اندر ایک عجیب دلکشی رکھتی ہے
اور اس میں گہری حکمتیں پوشیدہ ہیں.اس میں میاں بیوی دونوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے
کہ وہ باہم ایک دوسرے کے لئے اور اپنے بچوں کے لئے یہ دعا کرتے رہیں کہ
اللہ تعالیٰ ہمیشہ انہیں ایک دوسرے کی طرف سے اور بچوں کی طرف سے اطمینان اور
مسرت کی نعمتوں سے سرفراز کرے اور ان کی اولاد اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنے والی اور
متقی نسلوں کی پیش رو اور امام ہو.ایک شخص کو اس آیت کی اہمیت کا پوری طرح
اندازہ بھی ہو سکتا ہے جب وہ اس تعلیم پر خود عمل کرتا ہو.کسی چیز کے لئے ایک موہوم
سی خواہش آپ کے کردار پر کوئی خاص اثر نہیں ڈال سکتی.لیکن جب آپ پوری
128
Page 141
دلجمعی سے اپنی خواہش کی تکمیل کے لئے دعا کرتے ہیں تو اس دعا کا اثر لازما آپ
کے کردار اور طرز عمل پر پڑتا ہے.مثال کے طور پر ہم میں سے بہت سے ہیں جو
ہمیشہ سچ بولنا چاہتے ہیں مگر ان کی یہ خواہش کبھی کبھار ہی عمل کا روپ دھارتی ہے.لیکن جو لوگ پورے اخلاص اور صدق دل سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ وہ
انہیں ایک سچا انسان بنادے ان کی دعا ئیں ان کے کردار پر ان لوگوں کی نسبت کہیں
زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں جو سچا انسان بننے کی محض ایک مبہم سی خواہش رکھتے ہیں.خلوص دل سے دعا کرنے والا اپنے عمل میں بہتری پیدا کرنے کی سچی کوشش کرتا
ہے.تربیت اولاد کی دعا کے بعد اگر کوئی شخص اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ایسا سلوک
کرے گا جو اس دعا کے ساتھ مطابقت اور مناسبت نہ رکھتا ہو تو یہ ایک عجیب و غریب
اور نا قابل فہم سی بات ہوگی.قرآن کریم خاص طور پر نوجوان نسل کے حقوق اور ان کی تربیت سے متعلق ذمہ
داریوں کے بارہ میں متنبہ کرتے ہوئے فرماتا ہے.يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ : وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ
280
اللهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (سورة الحشر آیت ۱۹)
ترجمہ.اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو! اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور ہر
جان یہ نظر رکھے کہ وہ کل کے لئے کیا آگے بھیج رہی ہے.اور اللہ کا
تقویٰ اختیار کرو.یقیناً اللہ اس سے جو تم کرتے ہو ہمیشہ باخبر رہتا ہے.اس آیت میں والدین کو متنبہ کیا گیا ہے کہ اگر وہ ایسی اولاد کی تربیت کے سلسلہ
میں عائد ذمہ داریوں کی ادائیگی میں ناکام رہیں گے اور ایک ایسی نسل اپنے پیچھے
چھوڑیں گے جس کا کردار قابل مذمت ہوگا تو وہ اس کے لئے خدا کے سامنے جوابدہ
ہونگے.اسی طرح والدین کو خبردار کیا گیا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو قتل نہ کریں.اس
129
Page 142
سے مراد یہ ہے کہ والدین ہی ہیں جو اولاد کی صحیح تربیت نہ کرنے کے نتیجہ میں ان
کے اخلاق کو تباہ کر کے گویا ان کے قتل کا ذریعہ بن جاتے ہیں جس کے لئے وہ اللہ
کے سامنے جوابدہ ہیں.( مثلاً دیکھیں سورۃ الانعام آیت ۱۵۲)
حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پر زور نصیحت فرمائی ہے کہ نہ صرف
اپنے بچوں سے بلکہ نئی نسل کے سب بچوں اور نو جوانوں سے پیار محبت اور تکریم کے
ساتھ پیش آیا کریں.آپ نے فرمایا.اكرموا أولادَكُمْ (ابن ماجه، كتاب الأدب باب برالوالد والإحسان إلى البنات)
یعنی اپنی اولاد کے ساتھ محبت اور پیار اور احترام کے ساتھ پیش آیا کرو.یہی وہ تعلیم ہے جس کی آج کی دنیا کو ضرورت ہے.آج کل برطانیہ میں بڑی
سنجیدگی سے ایک ایسا قانون بنانے پر بحث کی جا رہی ہے جس کی رو سے والدین کو
اپنے بچوں کے جرائم کا بالواسطہ ذمہ دار ٹھہرایا جا سکے گا اور ان کے ساتھ ویسا ہی
سلوک کیا جائے گا جیسا عدالتیں کمسن مجرموں کے ساتھ کیا کرتی ہیں.یہ بات بڑی
شدت کے ساتھ محسوس کی جا رہی ہے کہ اگر والدین اپنے بچوں کی تربیت کی
ذمہ داری زیادہ سنجیدگی سے ادا کرتے تو برطانیہ کے گلی کوچوں میں جرائم کی تعداد کم
ہو جاتی.لیکن سوال یہ ہے کہ جب مذہب کے سکھائے ہوئے اخلاق ذہنوں میں
اچھی طرح سے راسخ نہ ہوں تو محض سزائیں دینے سے معاشرہ کی حالت کہاں تک
بہتر بنائی جاسکتی ہے.بے مقصد اور فضول مشاغل کی حوصلہ شکنی
قرآن مجید معاشرتی اصلاح کے مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے فرماتا ہے:
والَّذِين هم عنِ اللَّغْوِ مَعْرِضُونَ (سورۃ المومنون آیت ۴)
130
Page 143
ترجمہ.اور وہ جولغو سے اعراض کرنے والے ہیں.اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عقل مند لوگ اپنی قوتوں اور صلاحیتوں کو
بے کار اور بے معنی مشاغل میں ضائع نہیں کرتے.ہلکی پھلکی تفریح کے لئے کچھ وقت
نکال لینا کوئی بری بات نہیں اور نہ ہی اسلام اس سے منع کرتا ہے.لیکن اگر اس قسم کی
تفریح سے معاشرہ پر بحیثیت مجموعی برے اثرات مرتب ہوتے ہوں تو پھر یقیناً اس کی
حوصلہ افزائی نہیں کی جائے گی.تفریح کا مقصد تو زندگی کی مصروفیات کے باعث پیدا
ہونے والے ذہنی دباؤ اور پریشانیوں میں کمی کرنا ہے لیکن اگر تفریح فی ذاتہ ایک
مقصد بن جائے تو قرآن کریم کی اصطلاح میں اسے لغو کہا جائے گا جس کے معنی
بے کار، فضول اور بے مقصد کام کے ہیں.جب تفریح زندگی کے اہم معمولات میں
حارج ہو اور اس کے نتیجہ میں وہ قیمتی وقت ضائع ہو جس کا کوئی اور بہتر مصرف ہونا
چاہئے تھا تو ایسی تفریح کو بھی عربی لغت کی رو سے لغو ہی کہا جائے گا.اس امر میں کوئی شک نہیں کہ ٹیلی ویژن کے ذریعہ بہت سے فوائد حاصل ہوئے
ہیں.مگر بالعموم یہ دیکھا جاتا ہے کہ بچے سارا سارا دن ٹیلی ویژن کی سکرین پر نظریں
جمائے بیٹھے رہتے ہیں.لوگ اپنے کام سے واپس گھر لوٹتے ہیں تو خواہ کیسا ہی
پروگرام کیوں نہ دکھایا جا رہا ہوئی وی کے سامنے ڈیرہ ڈال دیتے ہیں.یہ کہنے کی
ضرورت نہیں ہے کہ ایسا کرتے وقت وہ اپنی ان ذمہ داریوں سے غافل ہوتے ہیں
جو ان کے بیوی بچوں، دوستوں اور بحیثیت مجموعی سارے معاشرہ کی طرف سے ان
پر عائد ہوتی ہیں.ٹی وی اپنے بے جا استعمال کی وجہ سے جدید دور کی ایک لعنت بن
چکا ہے.ٹیلی ویژن دیکھنے میں اس قدر وقت ضائع کر دیا جاتا ہے کہ یہ اندازہ لگانا
بے حد مشکل ہے کہ اس کے نقصانات زیادہ ہیں یا فوائد اور بات یہیں پر ختم نہیں
ہو جاتی.ٹی وی پر دکھائے جانے والے جرائم کو اس انداز سے پیش کیا جاتا ہے کہ
131
Page 144
بچوں کے دلوں میں جرم سے نفرت کی بجائے اس کی طرف رغبت پیدا ہونے لگتی
ہے.خاص طور پر بچوں کے لئے بنائے گئے پروگراموں میں بچوں کے مقبول کردار
ایسی ایسی چالاکیاں اور نا واجب شرارتیں کرتے ہوئے دکھائے جاتے ہیں جن کے
نتیجہ میں گھروں کا امن اور سکون برباد ہونے لگتا ہے.یہ پروگرام کتنے ہی دلچسپ
اور مزے دار کیوں نہ ہوں سبق آموز ہرگز نہیں ہوتے.بلاشبہ ٹیڑھے مزاج کے کئی
بچے ایسے ہی پروگراموں کی پیداوار ہیں اور ایسے بچوں میں مجرم بننے کی ایک مخفی
خواہش پہلے ہی سے کروٹیں لے رہی ہوتی ہے.بڑی عمر کے لوگوں کے لئے بھی جو ٹی وی پروگرام بنائے جاتے ہیں ان میں بھی
نا دانستہ طور پر جرم کے نئے سے نئے طریق سکھائے جاتے ہیں.ایک ایسی نکمی زندگی
کی منظر کشی کی جاتی ہے جو محض آرام طلبی اور کھیل کود سے عبارت ہے اور اس میں
ایسی رنگ آمیزی کی جاتی ہے کہ دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ زندگی ہو تو ایسی ہو.افسوس
کہ دیکھنے والے بھول جاتے ہیں کہ تخیل اور حقیقت کے مابین کتنے فاصلے حائل ہیں
اور نہیں جانتے کہ خوابوں کی دنیا حقیقی دنیا سے
کتنی مختلف ہوتی ہے.شاید بہت سے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو کہ قرآن کریم نے بیکار مشاغل اور بے سود
لذتوں کے پیچھے بھاگنے کی جو ممانعت کی ہے وہ ایک معمولی بات ہے لیکن درحقیقت
یہ ایک بہت بڑا اور اہم حکم ہے.ٹی وی اور تفریح کے دیگر ذرائع ایک ایسے ماحول
کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتے ہیں جس میں مایوسیاں اور ناکامیاں بڑھتی ہی چلی
جاتی ہیں اور انسان حیران ہوتا ہے کہ اس انحطاط کی آخری حد کیا ہوگی.خواہشات پر قابو پانا.قرآن کریم انسان کو اپنی خواہشات پر قابو پانے کی تلقین کرتا ہے.دوسروں کو
132
Page 145
دیکھ کر حسد کی آگ میں جلنا اور دل میں لا تعداد حسرتیں پال لینا اسلامی تعلیم کی رو
سے ناجائز ہے.انسان کو ضبط نفس سکھانے اور خواہشات کو محدود کرنے کے سلسلہ
میں یہ تعلیم اپنے اندر ایک بہت اہم پیغام رکھتی ہے.اسلام نہ تو زندگی سے فرار
سکھاتا ہے اور نہ ہی ایسی رہبانیت کی تعلیم دیتا ہے کہ تمام طبعی خواہشات کو مارکر
نروان حاصل کیا جائے.نروان کے فلسفہ کے مطابق خواہشات ہمیں مادیت میں جکڑ
دیتی ہیں اور اس کا غلام بنا دیتی ہیں.بالفاظ دیگر نجات کا ذریعہ یہی ہے کہ انسان
اپنی تمام خواہشات کو کچل ڈالے.اسلام اس فلسفہ کو رد کرتا ہے.اسلام کے نزدیک
یہ انسان کا بنایا ہوا ایک غیر طبعی فلسفہ ہے جو زندگی کے مسائل کا حقیقی حل نہیں ہے.نروان کا تصور اطمینان اور سکینت سے زیادہ موت کے قریب ہے.اس کے برعکس
اسلام نے ایک بالکل مختلف حل پیش کیا ہے جس کے مطابق طبعی خواہشات کو کچل کر
کوئی شخص زندگی کے راز کو نہیں پاسکتا.اسی طرح معاشرتی امن کے قیام کے لئے جو
بہت سے اقدامات تجویز کئے گئے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان اپنی
خواہشات کو کم کر کے ان کو نظم و ضبط کا پابند بنائے اور انہیں قابو میں رکھے.یہ ناممکن
ہے کہ انسان اپنی تمام خواہشات کی بے محابا تسکین سے حقیقی اطمینان اور سکینت
حاصل کر لے.جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے انسان جس تیز رفتاری سے خواہشات
کے پیچھے بھاگتا ہے خواہشات اس سے کہیں زیادہ تیزی سے آگے آگے بھاگتی ہیں.خواہشات کے طوفان کا مقابلہ کرنے کے لئے اسلام کے تجویز کردہ اقدامات ممکن
ہے بظاہر چھوٹے نظر آئیں مگر در حقیقت بہت اہم اور بہت مؤثر ہیں.مثال کے طور
پر قرآن مجید فرماتا ہے.و لیک -٥-٥
1-0
وَلَا تَمَدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلى مَامَتعنا به أَزْوَاجًا مِنهم زَهْرَةَ الْحَيوةِ الدُّنْيا لِنَفْتِنَهم
- b
10- w 200-
فِيهِ وَ رزق ربک خیر و ابقی
(سورۃ طہ آیت ۱۳۲ )
133
Page 146
ترجمہ.اور اپنی آنکھیں اس عارضی متاع کی طرف نہ پیار جو ہم نے ان
میں سے بعض گروہوں کو دنیوی زندگی کی زینت کے طور پر عطا کی ہے
تا کہ ہم اس میں ان کی آزمائش کریں.اور تیرے رب کا رزق بہت
اچھا اور زیادہ باقی رہنے والا ہے.قرآن کریم میں بدظنی ہنجس اور غیبت سے منع کیا گیا ہے.چنانچہ اللہ تعالیٰ
فرماتا ہے:
يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا
وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا
b
لو
فكرهتموهُ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ (سورة الحجرات آیت ۱۳)
ترجمہ.اے لوگو جو ایمان لائے ہو! بکثرت ظن سے اجتناب کیا کرو.یقیناً بعض ظن گناہ ہوتے ہیں.اور تجسس نہ کیا کرو.اور تم میں سے کوئی
کسی دوسرے کی غیبت نہ کرے.کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ
اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے ؟ پس تم اس سے سخت کراہت کرتے
ہو.اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرو.یقیناً اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا
(اور ) بار بار رحم کرنے والا ہے.عہد و پیمان اور معاہدات کا احترام
اسلامی معاشرہ میں باہمی عہد و پیمان کو بڑی اہمیت حاصل ہے.عہد کی پاسداری
اور بین الاقوامی معاہدات کے احترام کو اسلامی معاشرہ کی وحدت کے تصور کے لئے
ضروری سمجھا جاتا ہے.قرآن مجید مومنوں کی صفات کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے:
"
والَّذِين هم لاسنتِهِم وَعَهْدِهِم رَاعونَ (سورۃ المومنون آیت ۹)
ترجمہ.اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی نگرانی کرنے والے ہیں.134
Page 147
برائی کا خاتمہ.ایک اجتماعی ذمہ داری
لوگوں کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری حکومتوں کے سر نہیں ڈالی گئی بلکہ بحیثیت
مجموعی معاشرہ کے سب لوگوں پر عائد کی گئی ہے.یہ لوگوں کا فرض ہے کہ وہ برائی سے
بچیں اور نیک اعمال بجالائیں.ترقی یافتہ ممالک میں گھروں، گلیوں اور بازاروں سے کوڑا کرکٹ اکٹھا کر کے
اسے ٹھکانے لگانے کا کام چند مخصوص لوگوں کے سپرد ہوتا ہے.غریب ممالک میں
خاتون خانہ گھر کے کوڑا کرکٹ کو گلیوں میں پھینک دیتی ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ
راستے غلاظت سے اس قدر بھر جاتے ہیں کہ گزرنا دو بھر ہو جاتا ہے.گھروں کو پاک
صاف رکھنا بے شک گھر والوں کا فرض ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ گلیوں، محلوں اور
راستوں کی صفائی کا بھی کوئی باقاعدہ انتظام ضرور ہونا چاہئے.مغرب نے پبلک
مقامات کو صاف رکھنے کی سماجی ذمہ داری کی اہمیت کو جان لیا ہے مگر افسوس کہ وہ
جرائم کی نجاست سے معاشرہ کو پاک رکھنے کی انتہائی اہم ضرورت اور ذمہ داری کو
نہیں سمجھ سکے.یہ وہ گندگی اور نجاست ہے جو روزانہ گھروں سے نکل نکل کر گلیوں اور
بازاروں اور سارے معاشرہ کو آلودہ کر رہی ہے.اسلام نے سماجی ماحول کے اس مسئلہ کو بڑی جامعیت کے ساتھ بیان کیا ہے اور
اس کا حل تجویز فرمایا ہے.بدی کی نجاست کو کم سے کم کرنے کی اولین ذمہ داری گھر
کے بڑوں اور بزرگوں پر عائد ہوتی ہے.مقصد یہ ہے کہ معاشرہ میں پاکیزگی ہو نیکی
کو فروغ حاصل ہو اور بدی کی غلاظت کم ہو.دوسرے اسلام معاشرہ پر بھی یہ ذمہ
داری ڈالتا ہے کہ وہ انفرادی اور اجتماعی طور پر برائی کے خلاف ایک جہاد شروع
کرے.یہ جہاد نہ تو تلوار کے ذریعہ ہونا چاہئے اور نہ محض قانونی پابندیوں سے بلکہ
حکمت کے ساتھ لوگوں کو سمجھانا چاہئے اور مسلسل نصیحت کرتے چلے جانا چاہئے.135
Page 148
قرآن کریم کے نزدیک معاشرہ کو برائیوں سے پاک کرنے کا بہترین ذریعہ صبر کے
ساتھ لوگوں کو وعظ و تلقین کرتے چلے جانا ہے.فرمایا.٥٠٥٠٠
وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
(سورۃ آل عمران آیت ۱۰۵)
ترجمہ.اور چاہئے کہ تم میں سے ایک جماعت ہو.وہ بھلائی کی طرف
بلاتے رہیں اور نیکی کی تعلیم دیں اور بدیوں سے روکیں.اور یہی ہیں وہ
جو کامیاب ہونے والے ہیں.مذکورہ بالا آیت سے یہ نتیجہ نہیں نکالنا چاہئے کہ حکومت وقت لوگوں کی
اخلاقی صحت کو برقرار رکھنے کی ذمہ داری سے کلیتہ بری الذمہ ہو جاتی ہے.ایسا ہرگز
نہیں ہے.بلاشبہ قانون سازی اور قانون کے نفاذ کے اختیارات حکومت کے پاس
ہیں.میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام کے نزدیک صرف حکومتی مشینری جرائم کی
حوصلہ شکنی اور ان کی بیخ کنی کرنے کے لئے کافی نہیں ہے.ایک بار جب گھروں میں
اور معاشرہ میں مجرمانہ رجحانات کو بڑھنے اور پھیلنے کی اجازت دے دی جائے اور یہ
بیماری جڑ پکڑ جائے تو حکومت زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتی ہے کہ گاہے بگا ہے اس
بیماری کی بعض سطحی علامات کو دور کر دے.برائی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا حکومتوں کے
بس کا روگ نہیں.قانون کے لمبے ہاتھ بھی برائی کے گہرے بنیادی اسباب تک نہیں
پہنچ سکتے.پس بدی کا استیصال کرنے کی اولین ذمہ داری خاندان کے بزرگوں، مذہبی
لیڈروں اور عوامی رہنماؤں پر عائد ہوتی ہے.قرآن مجید کی مذکورہ بالا آیت اور اسی مضمون کی دیگر بہت سی آیات کو پیش نظر
رکھتے ہوئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ تم سے پہلے لوگ
بد انجام سے اس لئے دو چار ہوئے کہ انہوں نے نافرمانی اور سرکشی اختیار کی اور ایک
136
Page 149
دوسرے کو بدی کے ارتکاب سے نہیں روکا.آپ نے مزید فرمایا.تم پر لازم ہے کہ نیکی کا حکم دو اور بری باتوں سے لوگوں کو روکو.اور ظالم
کا ہاتھ پکڑ لو اور اسے عدل سے کام لینے پر آمادہ کرو اور اسے حق پر مضبوطی
سے قائم کرو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو باہم مشابہ کر دے گا اور تم پر
ویسے ہی لعنت کرے گا جیسا کہ اس نے ان ( پہلوں ) پر لعنت کی
(سنن ابودائود وسنن الترمذی ابواب الفتن ، باب ماجاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر )
آنحضرت ﷺ کے ارشاد کے مطابق کسی قوم کے تنزل کی ایک خطرناک
علامت یہ ہے کہ لوگ بدی کے اعلانیہ ارتکاب کے خلاف ناپسندیدگی اور نفرت کے
اظہار کی جرات کھو دیتے ہیں.حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث
میں ایسے معاشرہ کے افراد کو ایک کشتی کے مسافروں سے تشبیہ دی ہے.حضرت نعمان بن بشیر بیان کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا:
اس شخص کی مثال جو اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم رکھتا ہے اور جو ان کو توڑتا
ہے ان لوگوں کی طرح ہے جنہوں نے ایک کشتی میں جگہ حاصل کرنے
کے لئے قرعہ ڈالا.کچھ لوگوں کو اوپر کا حصہ ملا اور کچھ کو نیچے کی منزل میں
جگہ ملی.جو لوگ نیچے کی منزل میں تھے وہ اوپر والی منزل سے گزر کر پانی
لیتے تھے.پھر انہیں خیال آیا کہ خواہ مخواہ ہم اوپر کی منزل والے لوگوں کو
تکلیف دیتے ہیں.کیوں نہ ہم نیچے کی منزل میں سوراخ کر لیں اور
وہاں سے پانی لے لیا کریں.اب اگر اوپر والے ان کو ایسا احمقانہ فعل
کرنے دیں تو سب غرق ہوں گے اور اگر ان کو روک دیں تو سب بیچ
جائیں گے.(صحیح البخاری.کتاب الشهادات.باب القرعة في المشكلات )
مجھے ڈر ہے کہ یہ تمثیل بڑی حد تک عصر حاضر کے معاشروں پر صادق آتی ہے.137
Page 150
اوامر و نواہی
بعض دیگر سماجی ذمہ داریوں سے تعلق رکھنے والی آیات مندرجہ ذیل ہیں.ان
پر عمل کے نتیجہ میں معاشرتی امن کو فروغ ملتا ہے.وَعِبَادَ الرَّحْمنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجُهَلُونَ قَالُوا
سلمان
(سورۃ الفرقان آیت ۶۴)
ترجمہ.اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر فروتنی کے ساتھ چلتے ہیں
اور جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو (جوابا) کہتے ہیں سلام.وَإِذَا حَيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَدُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَورِدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
حَسِيبًا
(سورۃ النساء آیت ۸۷)
ترجمہ.اور اگر تمہیں کوئی خیر سگالی کا تحفہ پیش کیا جائے تو اس سے بہتر
پیش کیا کر دیا وہی لوٹا دو.یقیناً اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے.وَلَا تُصَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ
مُخْتَالٍ فَخُوره وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، إِنَّ أَنْكَرَ
الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْر
(سورۃ لقمان آیات ۲۰،۱۹)
ترجمہ.اور (نخوت) سے انسانوں کے لئے اپنے گال نہ پھلا اور زمین
میں یونہی اکڑتے ہوئے نہ پھر.اللہ کسی تکبر کرنے والے اور فخر و مباہات
کرنے والے کو پسند نہیں کرتا.اور اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر اور
اپنی آواز کو دھیما رکھ.یقیناً سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے.اسلام جو اخلاق اور کردار ایک مسلمان کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے وہ بجائے خود
ہر قسم کے غیر ذمہ دارانہ طرز عمل اور جرائم کا سد باب کرتا ہے.اسلام سماجی ماحول
138
Page 151
کے لئے ایک ایسی صحت مند زمین تیار کرتا ہے جو غلط رجحانات کی نشو ونما کے لئے
ساز گار نہیں ہوتی.اس مقصد کے حصول کے لئے اسلام نے اوامر و نواہی کی شکل میں
ایک مفصل اور جامع تعلیم عطا کی ہے.ان اوامر ونواہی کی تعداد سینکڑوں تک جا پہنچتی
ہے.اسلامی تعلیم کا مرکزی اور بنیادی حصہ قریباً تمام مذاہب میں مشترک ہے.پس
اختلافی عقائد سے صرف نظر کرتے ہوئے ان قرآنی آیات کے چند ایک حوالہ جات
پیش کرتا ہوں جن میں بعض اوامر و نواہی کا ذکر آتا ہے.اوامر
عصمت و پاکدامنی: سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر ۳۳.المومنون آیات ۶ تا ۸.النور آیات ۳۱، ۳۴ ۶۱ - الفرقان آیت ۶۹ - الاحزاب آیت ۳۶- المعارج آیات ۳۰ تا ۳۲
صفائی: البقرة آیت ۲۲۳ - النساء آیت ۴۴.المائدہ آیت ۷.الحج آیت ۳۰ - المدثر آیات ۶،۵
غصہ پر قابو پانا : آل عمران آیت ۱۳۵
تعاون: المائدة آیت ۳
ہمت و شجاعت : البقرة آیت ۱۷۸ - آل عمران آیات ۱۷۳ تا ۱۷۵.التوبہ آیت ۴۰.طہ آیات ۷۴۴۷۳.الاحزاب آیت ۴۰.الاحقاف آیت ۱۴
نیکی کرنا : البقرۃ آیت ۱۹۶ - آل عمران آیت ۱۳۵.المائدہ آیت ۹۴.الاعراف آیت ۵۷
امر بالمعروف اور نہی عن المنکر : آل عمران آیت ۱۱۱
نیکیوں میں مسابقت : البقرۃ آیت ۱۴۹
139
Page 152
امانتوں کا لوٹانا : البقرة آیت ۲۸۴ - النساء آیت ۵۹ - المومنون آیت ۹.المعارج آیت ۳۳
بھوکوں کو کھانا کھلانا : الدھر آیت ۹ - البلد آیات ۱۷ تا ۲۵
عفو و درگزر : البقرة -۱۰ آل عمران آیات ۱۶۰٬۱۳۵.النساء آیت ۱۵۰.المائدہ آیات ۹۷ - ابراہیم آیت - الزمر آیات ۶۸۴۸ - الاحقاف آیت ۱۶
سچی گواہی دینا: النساء آیت ۱۳۶.المائدۃ آیت ۹ - الفرقان آیت ۷۳
ملازموں کے ساتھ حسن سلوک: النساء آیت ۳۷
ہمسائیوں کے ساتھ حسن سلوک: النساء آیت ۳۷
رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک: البقرۃ آیت ۱۷۸.النحل آیت ۹۱.الروم آیت ۳۹
شکر : البقرة آیات ۱۷۳٬۱۵۳ ۱۸۶.آل عمران آیت ۱۴۵.المائدہ آیات ۷ ، ۹۰ - ابراہیم آیت ۸ - الزمر آیات ۸، ۶۷ - الاحقاف آیت ۱۶
عاجزی: الانعام آیت ۶۴ - الاعراف آیات ۱۴۷،۵۶،۱۴.النحل آیات.بنی اسرائیل آیت ۳۸ - القصص آیت ۸۱.لقمان آیات ۲۰،۱۹.۰،۲۴
المؤمن آیت ۳۶
عدل : المائدة آیت ۹ - الانعام آیت ۱۵۳ - انحل آیت ۹۱ - الحجرات آیت ۱۰
لوگوں کے درمیان صلح کروانا: النساء آیت ۱۱۵.الحجرات آیت ۱۰
صبر : البقرة آیات ۱۷۸٬۱۵۶٬۱۵۴٬۴۶.ہود آیت ۱۲ - الرعد آیت ۲۳.النحل آیات ۱۲۸٬۱۲۷ - القصص آیت ۸۱ - العنکبوت آیت ۶۱.الزمر آیت ۱۱.الشوریٰ آیت ۴۴- العصر آیت ۴
ثابت قدمی : الرعد آیت ۲۳ - حم سجده آیات ۳۱ تا ۳۳
140
Page 153
طہارت و پاکیزگی : البقرة آیت ۲۲۳.المائدة آیت ۷.التوبہ آیات
۱۰۳ ، ۱۰۸ - النور آیت ۲۲ - الاحزاب آیت ۳۴ - المدثر آیت ۵ - الاعلیٰ آیت ۱۵.الشمس آیات ۱۱۱۰
ضبط نفس : النساء آیت ۱۳۶.الاعراف آیت ۲۰۲.الکھف آیت ۲۹.الروم آیت ۳۰ - ص آیت ۲۷ - النازعات آیات ۴۲۴۴۱
اخلاق الزمر آیات ۳ تا ۴ البینه آیت ۶ - الماعون آیات ۵ تا ۷
سچائی: النساء آیت ۱۳۶.المائدة آیت ۱۲۰.التوبہ آیت ۱۱۹.بنی اسرائیل آیت ۸۲ - الحج آیت ۳۱ - الفرقان آیت ۷۳.الاحزاب آیات
۳۶،۲۵، ۷۱ - الزمر آیت ۳۳
ایثار : البقرة آیات ۲۰۸، ۲۶۳.ہود آیت ۵۲ - الحشر آیت ۱۰.التغابن آیت ۱۷.الدھر آیات ۱۰٬۹.اللیل آیات ۲۱۴۲۰
نواہی
بدکاری: بنی اسرائیل آیت ۳۳
خود پسندی، تکبر : البقرة آیات ۸۸،۳۵ - النساء آیت ۱۷۴.الاعراف آیت ۳۷
غیبت : الحجرات آیت ۱۳
فخر و مباہات : الحدید آیت ۲۴
تحقیر کرنا : الحجرات آیت ۱۲
تمسخر و استهزاء: الحجرات آیت ۱۲
مایوسی : الزمر آیت ۵۴
حسد الفلق آیت ۶
141
Page 154
اسراف : الاعراف آیت ۳۲.بنی اسرائیل آیات ۲۸٬۲۷
جاہلا نہ تقلید : بنی اسرائیل آیت ۳۷
غرور و تکبر: بنی اسرائیل آیت ۳۸.المومنون آیت ۷ ۴.لقمان آیت ۱۹
ناپ تول میں کمی : المطففین آیات ۲ تا ۴
برے نام رکھنا : الحجرات آیت ۱۲
بجل: النساء آیت ۳۸.محمد آیت ۳۹.الحدید آیات ۲ تا ۵ - الحشر آیت ۱۰.التغابن آیت ۱۷
خیانت النساء آیات ۱۰۶ ، ۱۰۸.الانفال آیات ۲۷، ۵۹
بدظنی : الحجرات آیت ۱۳
جھوٹ : الحج آیت ۳۱.الفرقان آیت ۷۳
چوری المائدة آیت ۳۹
اسلام تمام مذاہب کے راہنماؤں کو دعوت دیتا ہے کہ وہ مل جل کر کوشش کریں
که نیکی کو فروغ حاصل ہو اور وہ دلوں میں راسخ ہو جائے اور لوگوں کو بدی کے خلاف
متنبہ کیا جائے.کاش ایسا ہو سکے تاکہ دنیا کی حالت سنور جائے.اسلام نسل پرستی کورڈ کرتا ہے
موجودہ دور میں نسل پرستی ایک ایسی لعنت ہے جو امن عالم کے لئے سب سے
بڑا خطرہ ہے.قرآن کریم نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ تمام بنی نوع انسان کو یہ حقیقت
یاد دلاتا ہے کہ
يَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ مِّنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
142
Page 155
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَآءَ لُوْنَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ
(سورۃ النساء آیت ۲)
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا
ترجمہ.اے لوگو! اپنے رب کا تقویٰ اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان
سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا اور پھر ان دونوں میں سے
مردوں اور عورتوں کو بکثرت پھیلا دیا.اور اللہ سے ڈرو جس کے نام کے
واسطے دے کر تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو اور رحموں (کے تقاضوں )
کا بھی خیال رکھو.یقینا اللہ تم پر نگران ہے.پس قرآن کریم یہ اعلان کرتا ہے کہ کسی شخص کو کسی دوسرے پر بحیثیت انسان کوئی
برتری حاصل نہیں ہے.فرمایا.يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَّ انْثَى وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا.280-
280
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَكُمْ ، إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ
(سورۃ الحجرات آیت ۱۴)
ترجمہ.اے لوگو! یقیناً ہم نے تمہیں نر اور مادہ سے پیدا کیا اور تمہیں
قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کیا تا کہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو.بلاشبہ
اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی
ہے.یقینا اللہ دائمی علم رکھنے والا (اور ) ہمیشہ باخبر ہے.يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٍ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنهم
سه و یک
وَلا
نِسَاءٌ مِنْ نِّسَاءِ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا
وو
بالا لقَابِ بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الإِيْمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ
الظلمون
( سورة الحجرات آیت ۱۲)
ترجمہ.اے لوگو جو ایمان لائے ہو! (تم میں سے ) کوئی قوم کسی قوم پر
تمسخر نہ کرے.ممکن ہے وہ ان سے بہتر ہو جائیں.اور نہ عورتیں
143
Page 156
مختلف
عورتوں سے (تمسخر کریں).ہوسکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو جائیں.اور اپنے لوگوں پر عیب مت لگایا کرو اور ایک دوسرے کو نام بگاڑ کر نہ
پکارا کرو.ایمان کے بعد فسوق کا داغ لگ جانا بہت بری بات ہے.اور جس نے تو بہ نہ کی تو یہی وہ لوگ ہیں جو ظالم ہیں.سطحی نظر سے دیکھا جائے تو یوں لگتا ہے جیسے موجودہ معاشرہ رنگ ونسل کے
امتیاز سے دور ہٹتا چلا جا رہا ہے اور نسل پرستی کے خلاف دنیا کا ضمیر بیدار ہو رہا ہے
لیکن اگر اس مسئلہ کا زیادہ قریب سے اور گہرائی میں جا کر جائزہ لیا جائے تو معلوم
ہوگا کہ نسل پرستی کی لعنت آج بھی دنیا میں جگہ جگہ بدستور موجود ہے.مشکل یہ ہے
که نسل پرستی کی کوئی ایک جامع تعریف نہیں کی جاسکتی.مختلف تناظر میں یہ تعریف
دکھائی دینے لگتی ہے.نسلی عصبیت، ذات پات، مذہبی برتری کا احساس،
قبائلی تفاخر، فسطائیت، سامراجیت اور قوم پرستی میں حد فاصل کی تعیین مشکل ہے.مغربی یورپ میں عیسائیوں نے ایک ہزار سال یہود کے ساتھ انتہائی ظالمانہ اور
غیرانسانی سلوک روا رکھا ہے.ماضی کی یہ تکلیف دہ داستان بھول بھی جائیں تو
نازیوں کا یہود کے ساتھ وہ بہیمانہ سلوک کیسے بھلایا جا سکتا ہے جو انہوں نے اس
صدی کی تیسری اور چوتھی دہائی میں کیا.یہی وجہ ہے کہ نسل پرستی کا لفظ سنتے ہی بے
اختیار ہمارا ذہن یہود پر توڑے جانے والے مظالم کی طویل تاریخ کی جانب منتقل
ہو جاتا ہے.لیکن یہود کے ساتھ ہونے والے مظالم نسلی عصبیت کی پوری تصویر پیش
نہیں کرتے بلکہ اس تناظر میں کئی پہلو ہیں جو یکسر نظر سے اوجھل رہ جاتے ہیں.ہمیں کبھی ان انتہا پرست یہود کا خیال تک نہیں آتا جو غیر یہودی اقوام کے ساتھ
اسی قسم کی خوفناک عصبیت کا مظاہرہ کرتے ہیں جس کا وہ خود نشانہ بنتے رہے ہیں.اور یہ داستان یہیں ختم نہیں ہو جاتی.نسلی عصبیت کے کئی ایسے روپ بھی ہیں جو
144
Page 157
بظاہر دکھائی نہیں دیتے مگر در حقیقت موجود ہیں جن میں سے ایک قوم پرستی بھی ہے.علاوہ ازیں مذہبی، قبائلی اور علاقائی تعصبات وغیرہ کی بھی چند ایک ایسی مثالیں ہیں
جن میں پس پردہ نسلی عصبیت مختلف ناموں سے کارفرما ہوتی ہے.سفید فام لوگوں پر
یہ الزام عائد کرنا نا انصافی ہوگی کہ صرف وہی کالے اور زرد لوگوں سے تعصب
رکھتے ہیں.خود سیاہ فام اور زرد اقوام بھی نسل پرستی کا کچھ کم مظاہرہ نہیں کرتیں.اور پھر ایسی نسلی عصبیت بھی موجود ہے جس کا تعلق ان لوگوں سے ہے جن کی جلد کا
رنگ نہ تو سیاہ ہے اور نہ ہی بالکل زرد بلکہ دونوں کے بین بین ہے.نسل پرستی کے فساد کی جڑ دراصل طبقاتی تعصب ہی ہے اور غالباً یہی اس کی
موزوں ترین تعریف بھی ہے.جب بھی ایک طبقہ کے لوگ اپنے مفادات کی خاطر
دوسرے طبقہ کے خلاف تعصب برتنے لگتے ہیں تو نسلی عصبیت کا ناگ اپنا زہریلا اور
بھیا نک سر اٹھاتا ہے.پھر نفرتوں کی ایک ایسی آندھی چلتی ہے جو نیک و بد میں تمیز
نہیں کیا کرتی.اچھے برے، چھوٹے بڑے سب اس کی لپیٹ میں آجاتے ہیں اور
معاشرہ نفرتوں کی آماجگاہ بن جاتا ہے.چند صدیاں پہلے کرہ ارض کا مغربی حصہ بڑی حد تک عیسائیت اور اسلام کے
درمیان تقسیم تھا اور یہ دونوں مذاہب ایک دوسرے کے مقابل صف آرا تھے.مذہبی تعصب کے اس دور میں یہود نے مسلمانوں کے خلاف جو کردار ادا کیا وہ عام
طور پر لوگوں کے علم میں نہیں ہے تاہم اس حقیقت سے سب آگاہ ہیں کہ یہود
مسیحی یورپ ہی کا حصہ تھے اور یورپ بحیرہ روم کے گرد آباد مسلمان اقوام سے سخت
متنفر تھا اور ان کے متعلق ہمیشہ ہی بد اعتمادی کا شکار رہا.اہل یورپ مغرب کی جانب
مسلمانوں کی پیش قدمی سے خوفزدہ تھے.عیسائیوں اور مسلمانوں کے مابین اس شدید
مخالفت کے دور میں نسلی تعصب کا ایک ایسا عنصر بھی موجود تھا جس کی بنیاد رنگ کا
145
Page 158
اختلاف تھا.مسلمانوں اور عیسائیوں کی یہ کشمکش زیادہ تر ترک عرب اتحاد اور مسیحی
یورپ کے مابین ایک جنگ دکھائی دیتی ہے.جبکہ انڈونیشیا، ملائیشیا، چین اور
ہندوستان کے مسلمان اس جھگڑے سے بالکل لاتعلق اور الگ تھلگ رہے ہیں.اگر چہ بظاہر اس دور کی تاریخ ماضی کے دھندلکوں میں دفن ہو چکی ہے اور اس کی
یادیں انسانی حافظہ سے محو ہو چکی ہیں لیکن میں اس دبی ہوئی آگ کو پھر سے سلگتے
ہوئے دیکھ رہا ہوں.انسانی مسائل ہمیشہ کے لئے کبھی ختم نہیں ہوتے.یہ جھگڑے
تاریخ کے اندھیروں میں کیسے ہی گم کیوں نہ ہو چکے ہوں پھر بھی سر اٹھا سکتے ہیں.ماضی سے نکل کر زمانہ حال میں آجائیے.جب تک دنیا دو بڑی طاقتوں اور ان کے
اتحادیوں میں بٹی رہی مغرب کے مفاد کیلئے یہ ضروری تھا کہ اس قسم کے صدیوں
پرانے مسائل کو از خود نہ چھیڑا جائے اور نہ ہی کسی کو انہیں چھیڑنے کی اجازت دی
جائے لیکن جب سے مشرق اور مغرب کے مابین تعلقات کے ایک نئے دور کا آغاز
ہوا ہے یوں معلوم ہوتا ہے جیسے دنیا پھر سے قرون وسطی کے کسی جنگجو سردار کی
چیرہ دستیوں کا شکار ہونے والی ہے.سوویت یونین اور مشرقی یورپ میں رونما ہونے والی عظیم الشان تبدیلیوں نے
ایک ایسی فضا کو جنم دیا ہے جس سے عیسائیوں اور مسلمانوں کی پرانی مذہبی اور سیاسی
رقابتوں کے پھر سے ابھرنے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے.دونوں طرف کے مفاد پرست
اس آگ کو اور بھی ہوا دینے کا باعث بن سکتے ہیں.اور مجھے اندیشہ ہے بلکہ
غالب گمان ہے کہ اسلام اور عیسائیت دونوں کے مذہبی راہنما اس صورت حال کو اور
بھی زیادہ بگاڑ دیں گے اور یوں مسلمانوں اور عیسائیوں کے مابین امن اور ہم آہنگی
کے امکانات تاریک سے تاریک تر ہو جائیں گے.اگر ایسا ہوا تو اس کا فائدہ یقیناً
اسرائیل کو ہوگا.یہ ناممکن ہے کہ اسرائیل ایسی صورت حال میں کوئی دلچسپی نہ لے اور
146
Page 159
اسے خاموش تماشائی بن کر دور سے دیکھتا رہے.اب دنیا سیاسی اور معاشی بنیادوں پر
بھی تقسیم ہو چکی ہے.یہ تقسیم شمال کے امیر ممالک اور جنوب کے غریب ممالک اور
مشرق و مغرب کے درمیان ایک جدید قسم کے نسلی تعصب کو جنم دے رہی ہے.مشرق و مغرب کے درمیان حائل ان رقابتوں اور نفرتوں کے متعلق کسی نے کیا خوب
کہا ہے:
East is East and West is West, and never the twain
shall meet
یعنی مشرق مشرق ہے اور مغرب مغرب ہے اور یہ دونوں کبھی اکٹھے نہیں ہوسکیں
گے.عالمی طاقتوں کی محاذ آرائی میں حالیہ کمی اور دوستانہ تعلقات کی بحالی سے اس
بات کا امکان بھی ہے کہ مغرب کے عیسائی ممالک اور مشرق کے مسلمان ممالک کے
درمیان پائے جانے والے قدیم مذہبی اور سیاسی اختلافات اور رقابتیں پھر سے زندہ
ہو جائیں.بڑی طاقتوں کے مابین دوستانہ تعلقات کے استوار ہونے سے لازماً ایک
نیا استعمار وجود میں آئے گا اور ایک وسیع البنیا د نسلی عصبیت سر اٹھائے گی جس کے
باعث مشرق اور مغرب کے درمیان پائے جانے والے فاصلے اگر اور بھی بڑھ جائیں
تو اس پر تعجب نہیں ہونا چاہئے.ہو سکتا ہے کہ یہ مذکورہ بالا تفصیل نسل پرستی کی مسلمہ
تعریف سے تجاوز کرتی ہوئی دکھائی دے اور بعض لوگ یہ سمجھیں کہ میں نے
نسلی عصبیت کی تعریف کو ضرورت سے زیادہ وسیع کر دیا ہے اور ایسے امور کو بھی بحث
میں شامل کر لیا ہے جو بظاہر نسل پرستی سے تعلق نہیں رکھتے لیکن میں نسلی تعصب کے
محرکات کے گہرے اور غیر جانبدارانہ مطالعہ اور مشاہدہ کی روشنی میں کہہ سکتا ہوں کہ
کسی بھی غلط طرز عمل کو آپ نسلی عصبیت کہیں یا اسے کوئی اور شائستہ سا نام دے دیں
اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا.اگر پس پردہ عوامل ایک سے ہیں تو پھر مرض بھی دراصل
ایک ہی ہے خواہ اس کا نام کوئی سا کیوں نہ رکھ دیا جائے.نسلی عصبیت کو اگر وسیع تر
147
Page 160
معنوں میں دیکھا جائے تو اس سے مراد وہ گروہی تعصبات ہونگے جو ہمیشہ عدل و
انصاف کے راستہ میں حائل ہو جایا کرتے ہیں.امریکی اور روسی بلاکوں کے مابین محاذ آرائی میں اتنی تیزی سے جو حالیہ کمی آئی
ہے وہ دنیا کو ایک بالکل نئے دور کی طرف لے کر جا رہی ہے.یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ
اس آنے والے دور میں ہر قسم کے اختلافات مٹ جائیں گے لیکن افہام و تفہیم کے
نتیجہ میں دنیا کا ایک نیا نقشہ ابھر کر سامنے آ رہا ہے.جوں جوں نظریاتی اختلافات کی
شدت میں کمی آرہی ہے بین الاقوامی سطح پر پہلے سے موجود کچھ اور اختلافات اب
ابھر کر سامنے آئیں گے اور ان میں لازماً شدت پیدا ہوگی.جب سرمایہ دارانہ نظام
اور اشتراکی نظام کی رقابتیں عروج پر تھیں تو مشرق و مغرب کی روایتی تقسیم نسبتاً ثانوی
حیثیت اختیار کر گئی تھی اور یہ جھگڑے پس منظر میں چلے گئے تھے.لیکن اب
صورت حال بدل چکی ہے.اب مشرق اور مغرب کی وہی پرانی تقسیم ترقی یافتہ
مغرب اور پسماندہ مشرق کے درمیان ایک بار پھر نمایاں ہو کر سامنے آئے گی.مشرقی یورپ کے آزاد ہونے والے ممالک اور خود روس رفتہ رفتہ سرمایہ دارانہ
ممالک کے رنگ میں رنگین ہو جائیں گے اور بالآخر انہی کا حصہ بن کر تیسری دنیا کے
ممالک کے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو اس وقت سرمایہ دار ممالک کر رہے ہیں.اگر چه بیرونی منڈیوں پر قابض ہونے اور ان پر اپنی اجارہ داری قائم کرنے کے
لئے نئی نئی رقابتیں معرض وجود میں آئیں گی لیکن بحیثیت مجموعی مغرب پہلے سے کہیں
بڑھ کر ایک طاقتور سیاسی و اقتصادی وحدت بن کر ابھرے گا اور مشرقی بلاک بھی
بالآخر یورپ میں ہی مدغم ہو جائے گا اور یوں مشرق و مغرب کی روایتی تقسیم اور بھی
واضح اور گہری ہو جائے گی.مزید یہ کہ ایک نئی طرز کے سوشلزم کی وجہ سے قومیں افراد اور طبقات کی جگہ لے
148
Page 161
لیں گی.طبقاتی تقسیم اور طبقاتی کشمکش اب ایک ملک کے امراء اور غرباء کے درمیان
نہیں بلکہ امیر اور غریب قوموں کے مابین ہوگی.آئندہ کچھ عرصہ تک اس تباہ کن
تصادم کو دبایا تو جا سکتا ہے اور شائد اس کی شدت کو بھی کم کیا جا سکتا ہے لیکن اس سے
بچنے کی کوئی صورت نہیں.یہ بالآخر ہو کر رہے گا.مجھے خطرہ ہے اور یہ خطرہ بلاسبب
نہیں کہ ہم ایک بھیانک قسم کے عالمگیر نسلی عصبیت کے دور میں داخل ہو رہے ہیں اور
اندیشہ ہے کہ نسل پرستی کے ان شعلوں کو صیہونیت کی سیاسی قیادت اور بھی بھڑکائے
گی.حیفا یونیورسٹی کے نجمن بیت ہلا ہی نے ایک کتاب لکھی ہے:
"The Israeli Connection: Whom Israel arms and why" by
Benjamin Beit Heilahmi.Published in 1988 by I.B.Tauris
and Co.Ltd., London
اگر مصنف کے خیالات کو سنجیدگی سے لیا جائے اور صیہونیوں کے سوچے سمجھے
سیاسی فلسفہ کے متعلق اس کے پیش کردہ شواہد کو مستند سمجھا جائے تو امن عالم کے لئے
یقیناً یہ کوئی اچھا شگون نہیں ہے.عالمی امور میں اسرائیل نے جو کردار ادا کیا ہے اور
جو کردار ادا کرنے کا وہ ابھی ارادہ رکھتا ہے اس کا کچھ نہ کچھ اندازہ درج ذیل
اقتباسات سے ہوسکتا ہے.” اسرائیلی ریاست کے بانی ڈیوڈ بن گورین (David Ben Gurion)
نے جنوری ۱۹۵۷ء میں کہا کہ ہماری بقا اور حفاظت کے نقطہ نظر سے
ہمارے لئے کسی بھی یورپین ملک کی دوستی سارے ایشیا سے زیادہ اہمیت
رکھتی ہے.[Medzini ،۱۹۷۶ صفحہ ۷۵] صفحہ ۵
عربوں پر ازسرنو برتری حاصل کرنے کا صیہونی منصوبہ اور سامراجیت
کے زوال کو روکنے کا امریکی ہدف باہم یکجا اور ہم آہنگ ہو گئے ہیں.“
(صفحه ۲۰۵)
" آج دائیں بازو سے تعلق رکھنے والا شخص دل سے یہی چاہتا ہے کہ
149
Page 162
اسرائیل طاقتور ہوتا چلا جائے.وہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل اوزی (UZI)
جیسے مہلک ہتھیاروں سے لیس ہو کر تیسری دنیا کی ہر بنیاد پرست تحریک
اور طاقت پر فتح پاکر سیاہ فام اور زرد فام باشندوں کو تہہ تیغ کرتا
پھرے.یہی وجہ ہے کہ ارجنٹائن کے فوجی جرنیل اور پیراگوئے
(Paragoy) کے کرنل اور جنوبی افریقہ کے سفید فام بریگیڈیر
اسرائیلیوں سے محبت کرتے ہیں“.(صفحہ ۲۱۸)
امریکہ میں ۱۹۷۰ ء سے ” تیسری دنیا مردہ باد کا جو نعرہ بلند ہونا شروع
ہوا ہے وہ اسرائیلی عزائم ہی کی صدائے بازگشت ہے.اس تحریک کے
علمبردار Daniel Patrick Moynihan اور Jean Kirk
Patrick اسرائیل کو اپنا اعتمادی اور روح رواں سمجھتے ہیں“.(صفحہ ۲۲۲)
صیہونیت کے دائیں بازو کے دوسری جنگ عظیم سے قبل کے ایک لیڈر ولا ڈیمیر
جا یونسی (Vladimir Jabotinsky) واشگاف الفاظ میں صیہونیت اور
سامراجیت کے باہمی اتحاد کی باتیں کیا کرتے تھے.ان کا کہنا تھا کہ:
بحیرہ روم اور اس کے ارد گرد کا سارا علاقہ یوروپین اقوام کے قبضہ میں
رہنا چاہئے.یہ ہمارا عزم صمیم ہے مشرق و مغرب کے مابین
ہر جھگڑے میں ہم ہمیشہ مغرب کا ساتھ دیں گے کیونکہ منگولوں کے
ہاتھوں خلافت بغداد کی تباہی کے بعد گزشتہ ایک ہزار سال سے زائد
عرصہ سے مشرق کی نسبت مغرب ہی بہتر تہذیب و تمدن اور ثقافت کا
گہوارہ رہا ہے....اور آج ہم اس تہذیب و تمدن کے سب سے اہم
علمبردار ہیں.ہم قیامت تک عرب تحریک کی حمایت نہیں کر سکتے.یہ
تحریک ایک اسرائیل دشمن تحریک ہے اسے پہنچنے والی ہر زک اور
ہر شکست ہمارے لئے دلی مسرت کا باعث ہے.“
[1984 ,Brenner صفحات 75 تا 77 ] (صفحہ ۲۲۷)
150
Page 163
" تیسری دنیا کی آزادی کا تصور صیہونیت کی بنیادوں کے لئے ایک خطرہ
ہے.انسانی حقوق کے تصورات اسرائیل کے سیاسی نظام کے لئے
بے حد خطرناک ہیں.فلسطینیوں کے ساتھ کی گئی نا انصافیاں اتنی واضح
اور نمایاں ہیں کہ اس معاملہ کو سرعام زیر بحث نہیں لایا جا سکتا.اسرائیل
جو کچھ تیسری دنیا میں کر رہا ہے اس کا یقینی نتیجہ یہ ہوگا کہ دنیا کی توجہ
فلسطینیوں کے حقوق کی طرف ہو جائے گی.جب انسانی حقوق اور عالمی
انصاف کے معاملات زیر بحث آتے ہیں تو اسرائیلی ساری دنیا کو منافق
قرار دینے اور برا بھلا کہنے میں ذرہ بھر تامل نہیں کرتے.اس لحاظ سے
ان میں اور جنوبی افریقہ کے سفید فام باشندوں میں کوئی فرق نہیں
"
ہے.(صفحات ۲۳۶ ۲۳۷)
منیلا (فلپائن) سے ٹیگو سی گالیا Tegucigalpa ( ہونڈوراس
Honduras) تک اور نمیبیا میں ونڈھوئیک (Windhoek)
تک مسلسل جاری جنگ میں جو کہ در حقیقت ایک عالمی جنگ ہے اسرائیلی
ایجنٹوں کا ہاتھ ضرور ہوتا ہے.آخر وہ کونسا دشمن ہے جس کے خلاف
اسرائیل برسر پیکار ہے؟ یہ تیسری دنیا میں بسنے والی مخلوق ہے جنہیں ہرگز
یہ حق نہیں دیا جا سکتا کہ ان کا بر پا کردہ کوئی انقلاب کامیابی سے ہمکنار
ہو.“ (صفحہ ۲۴۳)
اسرائیل اپنے مستقبل کے سہانے خواب صرف اسی وقت تک دیکھ سکتا ہے
جب تک عرب دنیا اور تیسری دنیا کے ممالک باہمی تفرقہ کا شکار ہیں اور
کمزور ہیں.اس صورت حال میں کوئی تبدیلی اسرائیل کے لئے کوئی
اچھی علامت نہیں ہے.(صفحہ ۲۴۷)
اسرائیل کی برآمدات میں صرف ٹیکنالوجی، اسلحہ اور تجربہ کار ماہرین ہی
نہیں بلکہ ایک خاص قسم کی ذہنیت بھی شامل ہے.کامیاب تسلط جمانے
151
Page 164
کیلئے دنیا کو کس نظر سے دیکھنا ضروری ہے اور ظالم کی منطق کیا ہوتی ہے
یہ سب چیزیں بھی اسرائیل دنیا میں برآمد کرتا ہے.(صفحہ ۲۴۸)
امید واثق ہے کہ بالآ خر صیہونیت کے جنگی نعروں پر اسرائیلی قیادت کے سنجیدہ
طبقہ کی آواز غالب آجائیگی.اسرائیلی مصنفین میں سے غالباً حرکابی (Harkabi)
ہی ہے جسے سب سے زیادہ معقولیت پسند اور معتدل مزاج کہا جا سکتا ہے.وہ صیہونی
انتہا پسندوں کے جارحانہ طرز عمل کو صرف ناپسند ہی نہیں کرتا بلکہ اسے خود صیہونی
مفادات کے حق میں خودکشی کے مترادف قرار دیتا ہے.اگر چہ دیگر یہودی مفکرین
اور دانشور حرکابی کے نظریات سے پورے طور پر متفق نہیں ہیں لیکن بلاشبہ کسی مسئلہ
کے متعلق حرکابی کا نقطہ نظر زیادہ عملی اور حقیقت پسندانہ ہوتا ہے.خصوصا اس نے امن
کے لئے جو تجویز پیش کی ہے اس میں عربوں کے لئے امید کی ایک کرن ضرور دکھائی
دیتی ہے.میں یقین رکھتا ہوں کہ کسی بھی لحاظ سے اور کسی بھی سطح پر بنی نوع انسان کی تقسیم
اور امتیازی سلوک سے کچھ لوگ وقتی فائدہ تو حاصل کر سکتے ہیں لیکن بالآخر اس کے
دور رس نتائج سب کے لئے لازما برے ہی ہوا کرتے ہیں.عصر حاضر کے اس تناظر
میں اسلام ایک ایسا واضح اور امید افزا پیغام دیتا ہے جو موجودہ حالات میں بڑا مؤثر
کردار ادا کر سکتا ہے.اسلام نسل پرستی اور طبقاتی منافرت کی پرزور مذمت کرتا ہے
اور فساد کی کوئی بھی شکل کیوں نہ ہو اسے قابل مذمت قرار دیتا ہے.اس مضمون سے
متعلق قرآن کریم کی بہت سی آیات میں سے چند ایک قبل ازیں پیش کی جا چکی
ہیں.درج ذیل آیت کریمہ میں بانی اسلام حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
کے کردار کو اللہ تعالیٰ کا نور کہا گیا ہے.ایسا نور جو نہ صرف مشرق کیلئے ہے اور نہ ہی
صرف مغرب کیلئے بلکہ مشرق و مغرب دونوں کی یکساں بھلائی کیلئے آسمان سے اتارا
152
Page 165
گیا ہے:
ہو وہ و
28-
اللهُ نُورُ السَّمَوتِ وَالْأَرْضِ ، مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكُوةِ فِيْهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي
°
ط
زُجَاجَة - الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّى يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبَرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَّا
Jo
شَرْقِيَّةِ وَلَا غَرْبِيَّةِ » يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْلَمْ تَمْسَسْهُ نَاره نُور عَلى نُور
سلو
لا
يَهْدِى اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ ، وَ يَضْرِبُ اللهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيمٌ
(سورۃ النور آیت ۳۶)
b
ترجمہ.اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے.اس کے نور کی مثال ایک
طاق کی سی ہے جس میں ایک چراغ ہو.وہ چراغ شیشہ کے شمع دان میں
ہو.وہ شیشہ ایسا ہو گویا ایک چمکتا ہوا روشن ستارہ ہے.وہ (چراغ)
زیتون کے ایسے مبارک درخت سے روشن کیا گیا ہو جو نہ مشرقی ہو اور نہ
مغربی.اس کا تیل ایسا ہے کہ قریب ہے کہ وہ از خود بھڑک کر روشن ہو
جائے خواہ اسے آگ کا شعلہ نہ بھی چھوا ہو.یہ نور علی نور ہے.اللہ
اپنے نور کی طرف جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور اللہ لوگوں کے لئے
مثالیں بیان کرتا ہے اور اللہ ہر چیز کا دائمی علم رکھنے والا ہے.نیز قرآن مجید میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمۃ للعالمین قرار دیا گیا ہے
(سورۃ الانبیاء آیت ۱۰۸) جس کے معنی یہ ہیں کہ آپ ساری دنیا اور سب بنی نوع انسان
کے لئے سراپا رحمت ہیں.لیکن حیرت کی بات تو یہ ہے کہ قرون وسطی کا مزاج رکھنے
والے بہت سے مسلمان علماء جنہیں غلطی سے بنیاد پرست بھی کہا جاتا ہے یہ نظریہ
رکھتے ہیں کہ مسلمانوں کیلئے یہ ضروری ہے کہ وہ غیر مسلموں کے خلاف مسلح جہاد میں
مصروف رہیں یہاں تک کہ غیر مسلموں کا یا تو مکمل صفایا ہو جائے یا پھر وہ اسلام قبول
کر لیں.قرآن کریم جس اسلام کو پیش کرتا ہے اس کا جہاد کے اس بگڑے ہوئے
تصور سے دور کا تعلق بھی نہیں ہے.باب اول میں اس مضمون سے متعلق قرآن مجید
153
Page 166
کی کئی آیات درج کی جا چکی ہیں اس لئے انہیں یہاں دہرانے کی ضرورت نہیں.میں آخر میں اس بات کو پورے وثوق سے دہرا کر اس بحث کو ختم کرتا ہوں کہ
حقیقت یہی ہے کہ اسلام وحدت انسانی کا زبردست علم بردار ہے.اور اس کے
ساتھ ساتھ انسانی وحدت کے قیام اور امن عالم کو یقینی بنانے کیلئے پرامن اقدامات
تجویز کرتا ہے.حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سلسلہ میں جو
اسوہ حسنہ تھا اسے جاننے کے لئے خطبہ حجۃ الوداع میں سے لئے گئے چند اقتباسات
کافی ہیں.آپ نے اپنے وصال سے قبل بنی نوع انسان کے اجتماع سے جو کہ آپ
کی زندگی کا سب سے بڑا اجتماع تھا خطاب کرتے ہوئے فرمایا.” اے لوگو! میری بات کو غور سے سنو کیونکہ میں نہیں جانتا کہ آئندہ کبھی
میں اس میدان میں تمہارے سامنے تقریر کر سکوں گا یا نہیں.اللہ تعالیٰ
نے قیامت تک تمہاری جانوں اور مالوں کو ایک دوسرے کے لئے حرام
قرار دے دیا ہے.ہر شخص کے لئے وراثت میں اس کا حصہ مقرر کر دیا
گیا ہے.کوئی ایسی وصیت قبول نہیں کی جائے گی جس میں ایک جائز
وارث کے ساتھ نا انصافی کی گئی ہو.بچہ اسی کا ہوگا جس کے گھر میں وہ
پیدا ہوا ہے.ایک بدکار اگر بچہ کی ابوت کا دعوی کرے گا تو وہ اسلامی
قانون کے تحت سزا کا مستوجب ہوگا.جو شخص اپنے باپ کے سوا خود کو
کسی اور کی طرف منسوب کرتا ہے یا غلط بیانی سے کسی کو اپنا آقا قرار دیتا
ہے اس پر اللہ تعالیٰ ، اس کے فرشتوں اور تمام بنی نوع انسان کی لعنت
ہوگی.اے لوگو! تمہارے کچھ حقوق تمہاری بیویوں پر ہیں لیکن تمہاری بیویوں
کے کچھ حقوق تم پر بھی ہیں.ان پر تمہارا یہ حق ہے کہ وہ پاکیزگی اور
عفت کے ساتھ زندگی بسر کریں اور ایسے کام نہ کریں جو خاوندوں کیلئے
لوگوں میں بے عزتی کا موجب ہوں لیکن اگر وہ کوئی ایسی حرکت نہیں
154
Page 167
کرتیں جس سے خاوند کی عزت پر حرف آتا ہو تو پھر اپنی حیثیت کے
مطابق ان کی خوراک، لباس اور رہائش وغیرہ کا انتظام کرنا تمہاری
ذمہ داری ہے.ہمیشہ اپنی بیویوں سے حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نگہداشت تمہارے سپرد کی ہے.عورت کمزور
ہے اور اپنے حقوق کی حفاظت نہیں کر سکتی.شادی کے بعد اللہ تعالیٰ نے
ان کے حقوق کی ادائیگی تمہارے سپرد کی ہے.تم انہیں اللہ تعالیٰ کے
بنائے ہوئے قوانین کے مطابق اپنے گھر لائے تھے.پس خدا نے جو
امانت تمہارے سپرد کی ہے اس میں خیانت کے مرتکب نہ ہونا.اے لوگو! ابھی تک کچھ جنگی قیدی تمہارے قبضہ میں ہیں.پس میں تمہیں
نصیحت کرتا ہوں کہ ان کو ویسا ہی کھانا کھلاؤ جو تم خود کھاتے ہو اور ویسا
ہی لباس پہناؤ جو تم خود پہنتے ہو.اگر ان سے کوئی ایسا قصور سرزد
ہو جائے جسے تم معاف نہ کر سکو تو انہیں کسی اور کے سپرد کر دو.وہ بھی
اللہ تعالیٰ ہی کی مخلوق ہیں پس انہیں دکھ دینا یا تکلیف پہنچانا کسی طرح بھی
جائز نہیں ہو سکتا ہے...اے لوگو! جو کچھ میں تم سے
کہتا ہوں اسے سنو اور یاد رکھو.تمام مسلمان
آپس میں بھائی بھائی ہیں.تم سب برابر ہو.سب انسان خواہ وہ کسی قوم
اور کسی قبیلہ سے تعلق رکھتے ہوں اور کیسا ہی منصب کیوں نہ رکھتے ہوں
بحیثیت انسان برابر ہیں ( یہ کہتے ہوئے آپ نے اپنے دونوں ہاتھ
اٹھائے اور دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ملائیں اور فرمایا ) جس طرح ان
دونوں ہاتھوں کی انگلیاں برابر ہیں اسی طرح بنی نوع انسان آپس میں
برابر ہیں.کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ دوسرے پر کسی قسم کی برتری
کا دعوی کرے.تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو.اے لوگو! تمہارا خدا
ایک ہے اور تم ایک آدم کی اولاد ہو.کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت
حاصل نہیں ہے نہ کسی عجمی کو عربی پر فضیلت ہے.کسی کالے کو گورے پر
155
Page 168
کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے اور نہ کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت
ہے.ہاں فضیلت صرف اس حد تک ہے جہاں تک کوئی خدا اور اس کے
بندوں کے حقوق ادا کرتا ہے.تم میں سے سب سے زیادہ معزز وہی ہے
جو اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں سب سے زیادہ متقی ہے.جس طرح یہ مہینہ ، یہ دن اور یہ زمین مقدس ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے
ہر انسان کی جان، مال اور عزت کو مقدس قرار دیا ہے.کسی شخص کے
جان و مال اور عزت پر حملہ کرنا ایسا ہی غلط اور ناجائز ہے جیسے اس دن
اور اس مہینہ اور اس زمین کے تقدس کو پامال کرنا.یہ حکم صرف آج کے
لئے نہیں ہے بلکہ دائمی ہے.مجھے امید ہے کہ تم اسے یاد رکھو گے اورر
اس پر عمل پیرا رہو گے یہاں تک کہ تم اپنے پیدا کرنے والے خدا کے
حضور حاضر ہو جاؤ.آج جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے اسے دنیا کے کناروں تک پہنچا دو.ہو سکتا ہے جو لوگ یہ باتیں نہیں سن رہے وہ ان باتوں سے ان لوگوں کی
نسبت زیادہ فائدہ اٹھا ئیں جو سن رہے ہیں.(صحاح سته ، طبری، ابن هشام، خمیس، بیهقی)
اس عظیم الشان خطبہ کا یہ ایک نہایت فصیح و بلیغ اور پر شوکت اقتباس ہے.اس
میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات خاص طور پر ہمیں یاد دلائی ہے وہ
یہ ہے کہ ہم سب ایک آدم کی اولاد ہیں.اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ مختلف
مذاہب کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ اس عالمگیر وحدت انسانی کو پارہ پارہ کریں
جو ایک آدم کی اولاد ہونے کے ناطہ پیدا ہوتی ہے.156
Page 169
معاشرتی.اقتصادی امن
سرمایہ دارانہ نظام ، سوشلزم اور اسلام میں معاشی انصاف کا تصور
حمد تنگ دستی کے باوجود اعلیٰ مقاصد کے لئے خرچ کرنا
غرباء کے لئے خرچ کرنا
شکر گذاری کا جذبہ
نیکی کے اجر کی توقع کسی انسان سے نہ رکھنا.....بھیک مانگنا
مالی قربانی کے لئے طیب مال کی شرط
خدا کے راستہ میں اعلانیہ اور پوشیدہ خرچ.....معاشرتی ذمہ داریاں
حمد...تاریخ اسلام کا ایک واقعہ
خدا کی عطا کردہ سب نعمتوں میں سے خرچ کرنا.....خدمت خلق
شراب نوشی اور جوئے کی ممانعت
حمد شراب نوشی کے باعث ہونے والی اموات
حمد شراب نوشی کے باعث ہونے والے سالانہ اقتصادی نقصانات
157
Page 171
وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَ تَثْبِيتًا مِنْ
أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةِ بِرَبْوَةِ أَصَابَهَا وَابِل فَاتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنَ ۚ فَإِنْ
ده و
لَّمْ يُصِبْهَا وَابل " فَطَلّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ
(سورۃ البقرۃ آیت ۲۶۶)
ترجمہ.اور ان لوگوں کی مثال جو اپنے اموال اللہ کی رضا چاہتے ہوئے
اور اپنے نفوس میں سے بعض کو ثبات دینے کے لئے خرچ کرتے ہیں،
ایسے باغ کی سی ہے جو اونچی جگہ پر واقع ہو اور اسے تیز بارش پہنچے تو وہ
بڑھ چڑھ کر اپنا پھل لائے اور اگر اسے تیز بارش نہ پہنچے تو شبنم ہی بہت
ہو.اور اللہ اس پر جو تم کرتے ہو گہری نظر رکھنے والا ہے..زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ
b
الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ
الحيوةِ الدُّنْيَا = وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَابِ
ج
(سورۃ آل عمران آیت ۱۵)
ترجمہ.لوگوں کے لئے طبعا پسند کی جانے والی چیزوں کی یعنی عورتوں کی
اور اولاد کی اور ڈھیروں ڈھیر سونے چاندی کی اور امتیازی نشان کے
ساتھ دانے ہوئے گھوڑوں کی اور مویشیوں اور کھیتیوں کی محبت
خوبصورت کر کے دکھائی گئی ہے.یہ دنیوی زندگی کا عارضی سامان ہے.اہے وہ اللہ وہ جس کے پاس بہت بہتر لوٹنے کی جگہ ہے.159
Page 173
اسلام نے ان مقامات پر بھی ہمیں تفصیلی ہدایات دی ہیں جہاں سماجی اور معاشی
افق باہم ملتے ہوئے نظر آتے ہیں.اگر اسلام کی ان تعلیمات کو نافذ کیا جائے تو
ہمارے صبح و شام حسین اور دلکش ہو جائیں گے.سرمایہ دارانہ نظام ، سوشلزم اور اسلام میں معاشی انصاف کا تصور
معاشی انصاف کا نعرہ تو بڑا دلکش ہے اور فری مارکیٹ اکانومی رکھنے والا
سرمایہ دارانہ نظام اور جدلی مادیت کے فلسفہ پر قائم سائنٹفک سوشلزم دونوں یہی نعرہ
بلند کرتے ہیں.ایک طرف سرمایہ دارانہ نظام یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ
صرف اور صرف وہی معاشی انصاف فراہم کرتا ہے.دوسری طرف سائنٹفک سوشلزم
کا بھی یہی دعوئی ہے کہ اس کے سوا کوئی معاشی انصاف قائم نہیں کر سکتا.میں
معذرت کے ساتھ دونوں کے متعلق اپنی مایوسی کا اظہار کرتا ہوں کہ یہ دونوں ہی
معاشی انصاف کے سنہری اصول کو اپنانے اور اس پر عمل کرنے میں ناکام رہے ہیں.تا ہم اس موضوع پر تفصیلی بحث ہم آگے چل کر کریں گے.اسلام میں انصاف کا تصور بڑا وسیع اور ہمہ گیر ہے اور یہ تصور اسلامی تعلیم کے
سب پہلوؤں پر محیط ہے.لیکن صرف یہی نہیں بلکہ اسلام اس سمت میں ایک قدم اور
آگے بڑھتا ہے.سائنٹفک سوشلزم میں یہ کوشش کی جاتی ہے کہ معاشرہ کی اقتصادی
اونچ نیچ کو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے.امیر وغریب میں کوئی فرق باقی نہ رہے اور
سب لوگ قومی دولت سے یکساں فائدہ اٹھا ئیں.معاشرہ میں نہ غرباء ہوں اور نہ
ان کی ایسی ضروریات ہوں جو پوری نہ ہو سکیں.اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ حقوق کے
مطالبہ کا سوال ہی نہیں اٹھے گا اور امراء کو مفلوک الحال لوگوں سے یہ خطرہ نہیں ہوگا
161
Page 174
کہ وہ ان کی جمع کردہ دولت کو لوٹ لیں گے.جبکہ سرمایہ دارانہ نظام میں زیادہ تر
سب کے لئے یکساں مواقع مہیا کرنے کی بات کی جاتی ہے.وہ دولت کی مساوی
تقسیم کی بجائے فری اکانومی پر زور دیتے ہیں تا کہ سب کو اپنی کارکردگی دکھانے کے
لئے یکساں مواقع مل سکیں.اس طرح جو معاشرہ تشکیل پاتا ہے اس میں ہمیشہ لوگوں کو
اپنے مطالبات پیش کرنے کی ضرورت رہتی ہے.حکومت یا سرمایہ داروں سے زیادہ
سے زیادہ فوائد حاصل کرنے کے لئے پریشر گروپس بنائے جاتے ہیں، ٹریڈ یونینز کا
قیام عمل میں آتا ہے جو ملازموں اور مزدوروں کے حقوق کے لئے سرگرم عمل رہتی ہیں
لیکن اس کے باوجود ایسے معاشرہ میں ملازم اور مزدور پیشہ لوگ ہمیشہ ہی احساس
محرومی کا شکار رہتے ہیں.دوسری طرف اگر سائنٹفک سوشلزم کو مثالی شکل میں نافذ کیا
جائے تو معاشرہ کے کسی طبقہ کو کسی قسم کا مطالبہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی.یا تو معاشرہ اتنا آسودہ حال ہوگا کہ سب کی ضرورت کا خیال رکھتے ہوئے قومی دولت
کی منصفانہ تقسیم ممکن ہوگی.یا پھر معاشرہ اتنا غریب ہوگا کہ وہ کسی کی ضرورت کو پورا
نہیں کر سکے گا اور سب لوگ ایک ہی طرح کی بدحالی کا شکار ہوں گے.دونوں
صورتوں میں ایک ایسا معاشرہ تشکیل پائے گا جس میں حقوق کا مطالبہ ایک بے معنی
بات ہوگی جبکہ سرمایہ دارانہ نظام میں ہر طرف حقوق کے مطالبے نظر آتے ہیں.اس
نظام کے مطابق غرباء کو اپنی بے اطمینانی کے اظہار کا پورا حق ملنا چاہئے اور انہیں
ایسے مواقع بھی میسر آنے چاہئیں جہاں ان کی بات سنی جائے.پس اس صورت میں
انجام کار پریشر گروپس بنیں گئے ہڑتالیں ہوں گی اور آجر اور اجیر کے جھگڑے ہوں
گے اور کارخانوں پر تالے پڑ جائیں گے.اسلام ایک ایسا انداز فکر پیدا کرنا چاہتا ہے جس کے ذریعہ اہل اقتدار اور امراء
کو ہمیشہ یہ یاد رہے کہ ایک منصفانہ اقتصادی نظام کا قیام بالآخر ان کے اپنے مفاد
162
Page 175
میں ہے.اسلام ارباب حل و عقد اور اہل ثروت کو تاکید کرتا ہے کہ وہ ہمیشہ دوسروں
کے حقوق کا خیال رکھیں.کمزور طبقات اور غرباء کے بنیادی معاشی حقوق کبھی تلف نہ
ہونے دیں.پیشہ کے انتخاب کی آزادی یکساں مواقع اور بنیادی ضروریات زندگی
ان کے بنیادی حقوق ہیں جو انہیں ملنے چاہئیں.اس سوچ اور فکر کے فقدان سے
انسانوں نے زندگی کی جدوجہد میں بڑے دکھ اٹھائے ہیں اور تاریخ انسانی میں
فتنہ وفساد کے بے شمار سیاہ باب رقم ہوئے ہیں.معاشرہ کو ایسے دکھوں سے محفوظ رکھنے
کی خاطر اسلام نے جو تعلیم دی ہے اس میں لینے اور سمیٹنے سے زیادہ دینے پر زور دیا
گیا ہے.اہل اقتدار اور صاحب ثروت لوگوں کا فرض ہے کہ وہ ہمیشہ اس بات کی
نگرانی کرتے رہیں کہ معاشرہ کا کوئی طبقہ بنیادی انسانی حقوق سے اس حد تک محروم
نہ ہو کہ مناسب اور باعزت زندگی بھی نہ گزار سکے.ایک حقیقی اسلامی ریاست کا
فرض ہے کہ عوام کی بنیادی ضروریات کا پورا احساس رکھے اور ان کی فراہمی کے لئے
مناسب اقدامات کرے.اس سے پہلے کہ لوگوں کے سینوں میں دبے ہوئے دکھ
دکھائی دینے لگیں، خاموش غم فریاد کرنے لگیں اور انسانوں کی ضروریات نظام اور
معاشرہ کے امن کے لئے خطرہ بن جائیں وہ ضرورتیں پوری ہونی چاہئیں اور ان
غموں اور دکھوں کی وجوہات دور ہونی چاہئیں.بنیادی ضروریات زندگی مہیا کرنے کے لحاظ سے یہاں بظاہر اسلام اور سوشلزم
میں ایک گونہ مشابہت نظر آتی ہے لیکن در حقیقت یہ ایک سطحی مشابہت ہے.فرق یہ
ہے کہ اسلام اپنے مقاصد کے حصول کے لئے وہ جبری ذرائع استعمال نہیں کرتا جو
سائنٹفک سوشلزم نے تجویز کئے ہیں.اس مختصر وقت میں میں تفصیل سے تو یہ بیان
نہیں کر سکتا کہ اسلام کس طرح اس عظیم منزل کے حصول کو ممکن بنا تا ہے لیکن مختصراً
اتنا کہوں گا کہ اسلام جبری مادیت کے فلسفہ کی طرح اس مسئلہ کو ایک بے جان اور
163
Page 176
مشینی انداز میں نہیں لیتا.اسلام کا سماجی نظام انسانی نفسیات کے طبعی قوانین سے
پوری طرح ہم آہنگ ہے.دیگر باتوں کے علاوہ اسلام ایک ایسے ماحول کو پیدا کرتا
ہے جس میں اپنے حقوق کے مطالبہ کی جگہ دوسروں کے حقوق کا احترام پیدا ہو جاتا
ہے.ایک حقیقی اسلامی معاشرہ کے لوگ دوسروں کے دکھ درد کے بہتر شعور اور
احساس کی وجہ سے اپنے حقوق سے زیادہ ان تقاضوں کی فکر کرتے ہیں جو معاشرہ ان
سے کرتا ہے.حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متبعین کو بار بار یہ نصائح فرمائی
ہیں کہ مزدوروں کو ان کے حق سے زیادہ دو.مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک
ہونے سے پہلے دے دو.اپنے ماتحتوں سے محنت و مشقت کے ایسے کام نہ لوجن کی
خود تم میں تاب نہیں.جہاں تک ممکن ہو اپنے نوکروں کو ایسا ہی کھانا کھلاؤ جیسا تم
اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو اور ویسا ہی کپڑا پہناؤ جیسا تم خود پہنتے ہو.کمزور پر کسی
قسم کی زیادتی مت کرو ورنہ تم خدا کے سامنے جواب دہ ہو گے.کبھی کبھی اپنے
نوکروں کو اپنے ساتھ دستر خوان پر بٹھاؤ اور خود ان کے سامنے کھانا پیش کرو تا کہ تم
جھوٹے تکبر اور نخوت سے بچ سکو.تنگ دستی کے باوجود اعلیٰ مقاصد کے لئے خرچ کرنا
قرآن کریم نے انسانی عزت اور وقار کو قائم کرنے پر انتہائی زور دیا ہے.غریبوں اور حاجت مندوں کی ضرورتیں ان کی عزت نفس کو قائم رکھتے ہوئے کس
طرح پوری کرنی چاہئیں.اس کے متعلق مندرجہ ذیل آیت ایک ضابطہ اخلاق فراہم
کرتی ہے.اس میں ان صفات کا ذکر ہے جو احسان کرنے والوں میں ہونی چاہئیں
164
Page 177
اور انہی صفات کے حامل لوگوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کی آیت میں
بخشش اور مغفرت کے انعام کا ذکر کیا ہے.الله الله
الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ
سو و
وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِين
(سورۃ آل عمران آیت ۱۳۵)
ترجمہ :.(یعنی) وہ لوگ جو آسائش میں بھی خرچ کرتے ہیں اور تنگی میں
بھی اور غصہ دیا جانے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں.اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے.غرباء کے لئے خرچ کرنا.b
صدقہ و خیرات کے جو معنی عام طور پر سمجھے جاتے ہیں اس کے دو پہلو ہیں.ایک
طرف خیرات کرنے والے کی خوب تعریف و توصیف ہوتی ہے تو دوسری طرف
خیرات لینے والے کو اگر بے عزتی کا نہیں تو کم از کم خفت کا سامنا ضرور کرنا پڑتا
ہے.محض خیرات لینے کی وجہ سے وہ شخص اپنے مقام سے گر جاتا ہے اور اس کی
عزت میں کمی آجاتی ہے.اسلام نے ایک انقلابی رنگ میں صدقہ و خیرات کے اس
تصور کو یکسر تبدیل کر کے رکھ دیا ہے.قرآن کریم کی ایک آیت میں اس امر کا نہایت دلآویز تجزیہ پیش کیا گیا ہے کہ
کیوں معاشرہ میں کچھ لوگ بے حد امیر ہوتے ہیں اور کچھ انتہائی غربت کا شکار
ہو جاتے ہیں.فرمایا
و فِي أَمْوَالِهِم حَق للسّائِلِ وَالْمَحْرُومِ O (سورۃ الذاریات آیت ۲۰)
ترجمہ.اور ان کے اموال میں سوال کرنے والوں اور بے سوال
165
Page 178
ضرورت مندوں کے لئے ایک حق ہے.اس آیت میں لفظ حق کے مفہوم کو پوری طرح سمجھا نہیں گیا.یہ لفظ جہاں
صدقہ و خیرات کرنے والوں کو بتاتا ہے کہ محتاجوں اور غریبوں سے تمہارا کیا رویہ ہونا
چاہئے وہاں یہ لفظ خیرات لینے والوں کی سوچ کو بھی صحیح سمت دیتا ہے.خیرات دینے
والے کو یہ یاد دلایا گیا ہے کہ جو مال وہ غرباء کو دے رہا ہے وہ درحقیقت اس کا مال
نہیں ہے.نیز لفظ حق میں یہ پیغام دیا گیا ہے کہ خیرات قبول کرنے والے کو شرمندہ
ہونے یا کسی قسم کی ذہنی الجھن کا شکار ہونے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں.اللہ تعالیٰ
نے اسے یہ حق دیا ہے کہ وہ اچھے اور باعزت طریق پر زندگی بسر کرے.یہ کہنے کی
ضرورت نہیں کہ جس معاشرہ میں کچھ لوگ بالکل مفلس اور قلاش بن کر رہ جائیں یا
زندہ رہنے کے لئے بھیک مانگنے پر مجبور ہو جائیں وہ معاشرہ صحت مند نہیں کہلا سکتا.اس میں یقیناً کوئی ایسی خرابی ہو گی جس سے یہ بھیانک صورتحال پیدا ہوئی.ایک
صحت مند معاشی نظام میں کوئی شخص اتنا غریب نہیں ہونا چاہئے کہ وہ زندگی کی بنیادی
ضروریات سے بھی محروم ہو اور زندگی کی بقاء کے لئے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو.جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تعلیم فطرت انسانی کے
عین مطابق ہے.چنانچہ صدقہ و خیرات کے حکم سے اگر امکانی طور پر بعض لوگوں کی
خود داری اور عزت نفس پر حرف آ سکتا ہے تو قرآن کریم نے اس کے ازالہ کا سامان
بھی فرما دیا ہے اور اس طرح غرباء کو ہر قسم کی شرمندگی اور خفت سے بچالیا ہے.شکر گزاری کا جذبہ
غرباء کی مدد کو ان کا حق سمجھا جائے تو بین السطور یہ خطرہ ہمیشہ موجود رہتا ہے کہ
کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ لوگ الٹا احسان پر ناشکری کرنے لگیں.ان پر احسان کیا جائے
166
Page 179
تو وہ کہہ دیں کہ جو کچھ ہمیں دیا گیا ہے وہ ہمارا حق تھا اس لئے ہمیں کسی قسم کا شکریہ
ادا کرنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے.اگر یہ رجحان عام ہو جائے تو اس کے تو
یہی معنی ہوں گے کہ شائستگی اور اچھے اخلاق معدوم ہو گئے ہیں.یہی وجہ ہے کہ
قرآن کریم احسان قبول کرنے والے کو بار بار یاد دلاتا ہے کہ اس کا یہ فرض ہے کہ وہ
شکر گزار بنے.احسان خواہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو اسے چاہئے کہ اپنے محسن کا شکریہ
ادا کرے.ایک مومن کو بار بار یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ناشکرے انسان سے
محبت نہیں کرتا.إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللهَ غَنِى عَنْكُمْ وَلاَ يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ وَإِنْ تَشْكُرُوا.قف
ط و
يَرْضَهُ لَكُمْ وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا
ط
2280
وہ
( سورة الزمر آیت ۸)
كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ، إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِه
ترجمہ.اگر تم انکار کرو تو یقیناً اللہ تم سے مستغنی ہے اور وہ اپنے بندوں
کے لئے کفر پسند نہیں کرتا اور اگر تم شکر کرو تو وہ اسے تمہارے لئے پسند
کرتا ہے.اور کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی دوسری کا بوجھ نہیں اٹھائے گی.پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے.پس وہ تمہیں ان اعمال سے
باخبر کرے گا جو تم کیا کرتے تھے.یقیناً وہ سینوں کے رازوں کو خوب
جانتا ہے.آنحضرت شکر گزاری کی اہمیت پر مزید زور دیتے ہوئے مومنوں کو یاد
دلاتے ہیں.مَنْ لَّمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهَ
(سنن الترمذی ، ابواب البرّوا الصلة - باب ماجاء في الشكر لمن احسن الیک)
یعنی جو شخص انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ خدا کا بھی شکر ادا نہیں کرتا.167
Page 180
اس سے مراد یہ ہے کہ جو شخص بنی نوع انسان کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اگر خدا کا
شکر گزار ہو بھی تو اس کا شکر اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں کیا جائے گا.سورۃ الزمر کی
مذکورہ بالا آیت شائستگی اعلی اخلاق اور شکر گزاری کے جذبہ کی ہرگز حوصلہ شکنی نہیں
کرتی.اس آیت میں تو احسان قبول کرنے والے کو یہ خاموش پیغام دیا گیا ہے کہ
اسے کسی قسم کے احساس کمتری میں مبتلا ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی
احسان قبول کرنے سے اس کا وقار مجروح ہونا چاہئے.ہاں کسی کا شکر گزار ہونا نہ
صرف انسانی وقار کے منافی نہیں ہے بلکہ یہ تو ایک ایسی صفت ہے جو وقار میں اضافہ
کا باعث بن جاتی ہے.اسلام احسان کرنے والے کو بھی ایک بالکل مختلف اور منفرد
انداز اختیار کرنے کی تعلیم دیتا ہے.عام طور پر یہ بات وقار اور انکسار کے منافی سمجھی
جاتی ہے کہ شکریہ کو حق سمجھ کر قبول کیا جائے.ایسی کسر نفسی دکھا نا تہذیب کا حصہ ہے
لیکن اس عام مہذب انداز میں اور اسلام کی اعلیٰ اخلاقی تعلیم میں ایک بنیادی فرق
ہے.اسلام نیکی ، بھلائی اور خدمت خلق کا حکم اس لئے نہیں دیتا کہ ایسے کاموں کے
ذریعہ نیک نامی ہو یا فطری جذبہ خدمت کی تسکین کا سامان ہو جائے.اسلام کے
نزد یک خدمت خلق کا بلند تر مقصد صرف اور صرف رضائے باری تعالیٰ کا حصول
ہے.بار بار یہ تاکید کی گئی ہے کہ نیک کام محض اللہ ہونے چاہئیں تا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ
کی رضا حاصل ہو اور وہی اس کا اجر عطا فرمائے.اس سے یہ بات خوب واضح ہو جاتی ہے کہ جب ایک سچا اور حقیقی مسلمان کسی
حاجت مند کی حاجت پوری کرتا ہے تو اس کے پیش نظر کوئی ذاتی مفاد نہیں ہوتا نہ ہی
وہ کسی شخص کو خوش کرنا چاہتا ہے.بلکہ اس کا واحد مقصد صرف اپنے خالق اور مالک
خدا کو راضی کرنا ہوتا ہے.وہ اس خدا کی خوشنودی چاہتا ہے جس نے وہ سب کچھ
اسے عطا کیا جس کا وہ آج مالک ہے.168
Page 181
چنانچہ اس اصول کی روشنی میں جو کچھ بھی وہ دوسروں پر خرچ کرتا ہے وہ کوئی
احسان نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ کے ان احسانات کا شکر ادا کرتا ہے جو خود اس کی ذات
پر ہیں.اس شاندار فکر وعمل کی بنیا د قرآن کریم کی ایک ابتدائی آیت ہے جس میں کہا
گیا ہے کہ
و بما رزقنهم ينفقون
( سورة البقرة آیت ۴)
ترجمہ.اور جو کچھ ہم انہیں رزق دیتے ہیں وہ اس میں سے خرچ کرتے
ہیں.پس ایک سچا مومن اگر یہ نہیں چاہتا کہ کسی احسان کے بدلہ میں لوگ اس کا شکریہ
ادا کریں تو کسی کسر نفسی یا ظاہری تہذیب کی وجہ سے نہیں ہوتا.وہ تو حقیقتاً اس بات
کو اپنا جزو ایمان سمجھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے جس شخص پر احسان کیا ہے اس پر اگر
کسی کا شکر ادا کرنا واجب ہے تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے.یہی وجہ ہے کہ
حقیقی مومن جو ایمان کے مفہوم سے واقف ہیں جب کوئی ان کے احسانات کا شکریہ
ادا کرے تو وہ بے حد شرمندگی محسوس کرتے ہیں.قرآن مجید یہ اعلان کرتا ہے.05
لیک
ور ووه
وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيْنًا وَّ يَتِيمًا وَّاسِيْرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ
اللهِ لا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا (سورۃ الدھر آیات ۹ - ۱۰)
ترجمہ.اور وہ کھانے کو، اس کی چاہت کے ہوتے ہوئے ،مسکینوں اور
قتیموں اور اسیروں کو کھلاتے ہیں.ہم تمہیں محض اللہ کی رضا کی خاطر کھلا
رہے ہیں، ہم ہر گز نہ تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ کوئی شکریہ.محض کھانا کھلا دینا ہی کافی نہیں بلکہ زندگی کے آلام و مصائب اور بھوک کی
اذیت کو جانتے ہوئے ، لوگوں کے دکھوں میں شریک ہو کر اور کسی شکریہ کی توقع کے
بغیر کھانا کھلانا ایک حقیقی مومن کے شایان شان عمل ہے.مذکورہ بالا آیات کا حسن
169
Page 182
آنکھوں کو خیرہ کر دیتا ہے.اگر یہ تعلیم دی جاتی کہ مومن ایک سطحی انداز میں مصنوعی
عجز و انکسار دکھاتے ہوئے لوگوں کے شکریہ کو قبول کرنے سے انکار کر دیا کریں گویا
شکر یہ قبول کرنا ان کی شان کے منافی ہے تو اندیشہ تھا کہ اس طرح منافقت کو فروغ
ملے.جب ایک شخص رسما یہ کہتا ہے کہ شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں تو درحقیقت وہ جانتا
ہے کہ اس طرح وہ اس شخص کی نظروں میں اور بھی زیادہ معزز ہو جائے گا جس پر اس
نے احسان کیا.اس کے برعکس اسلام کی تعلیم کہیں زیادہ حسین اور پاکیزہ شان کی
حامل ہے.احسان کرنے والے کو یاد دلایا گیا ہے کہ وہ اپنے مال کو بیک وقت دو
خریداروں کے ہاتھ فروخت نہیں کر سکتا.نیکی کا کام یا تو رضائے الہی کی خاطر ہوسکتا
ہے یا پھر غیر اللہ کی خوشنودی کے لئے ہو سکتا ہے.یہ آیت بتاتی ہے کہ دونوں قسم کی
نیتیں ایک ہی وقت میں اکٹھی نہیں ہو سکتیں.خدا کا ایک مخلص بندہ جب کسی ضرورت
مند کی ضرورت کو پورا کرتے وقت یہ کہتا ہے کہ میری نیت تو درحقیقت صرف اللہ کی
رضا کا حصول ہے تو اس طرح وہ اس ضرورت مند کو بھی یاد کروا رہا ہوتا ہے کہ اس کا
حقیقی محسن وہ نہیں بلکہ اللہ کی ذات ہے.ظاہر ہے کہ سوچ کے اس انداز سے اس محتاج
انسان کے دل میں کسی قسم کے احساس کمتری کے پیدا ہونے کا امکان نہیں رہتا.نیکی کے اجر کی توقع کسی انسان سے نہ رکھنا
اسلامی تعلیم کے مطابق دوسرے سے اچھے اخلاق سے پیش آنا تہذیبی اقدار کے
زیر اثر اختیار کی ہوئی ایک سطحی عادت کے رنگ میں نہیں ہونا چاہئے بلکہ تمام اخلاق
کی جڑیں ایمان باللہ میں پیوست ہونی چاہئیں.محتاجوں کو صدقہ و خیرات اس گھٹیا
نیت سے نہیں دینا چاہئے کہ اس کے بدلہ میں ان سے بھی کبھی کوئی فائدہ حاصل کریں
170
Page 183
گے.ولا تمنن تستكثر
(سورۃ المدثر آیت ۷ )
ترجمہ.اور زیادہ لینے کی خاطر احسان نہ کیا کر.اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی پر احسان کیا ہے تو اسے یوں بھول
جائیں جیسے کچھ بھی نہیں ہوا.احسان جتانا اور نیکی پر فخر کرنا اور اسے بڑھا چڑھا کر
بیان کرنا نیکی کو برباد کر دیتا ہے.ایک حقیقی مومن ہرگز ایسا نہیں کرتا.اس کا طرز عمل
درج ذیل آیات میں بیان کیا گیا ہے.یہ آیات غلط اور صحیح طرزعمل میں بڑا جامع
موازنہ پیش کرتی ہیں.مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةِ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي
280 28
كُل سُنْبُلَةٍ سَائَةُ حَبَّةٍ ، وَاللهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ الَّذِيْنَ
طا
ط
يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيْلِ اللهِ ثُمَّ لاَ يُتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنَّا وَلَا أَذًى ا لَّهُمْ
ووه
28
وده وه
لا
آجرهم عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَO قَوْل مَعْرُوفَ " وَ
مَغْفِرَة خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى ، وَاللهُ غَنِي حَلِيمٌ يَا يُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
لا تُبْطِلُوا صَدَقَتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالَّا ذِى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَا لَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا
يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَان عَلَيْهِ تُرَابٍ فَأَصَابَهُ، وَابل
فَتَرَكَهُ صَلْدَاء لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
الْكَافِرِينَ
ط
( سورة البقرة آیات ۲۶۲ تا ۲۶۵)
ترجمہ.ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں
ایسے بیج کی طرح ہے جو سات بالیں اگا تا ہو.ہر بالی میں سو دانے
ہوں.اور اللہ جسے چاہے (اس سے بھی ) بہت بڑھا کر دیتا ہے.اور اللہ
وسعت عطا کرنے والا (اور ) دائمی علم رکھنے والا ہے.وہ لوگ جو اپنے
28
171
Page 184
اموال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر جو وہ خرچ کرتے ہیں اس کا
احسان جتاتے ہوئے یا تکلیف دیتے ہوئے پیچھا نہیں کرتے ان کا اجر
ان کے رب کے پاس ہے اور ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غم
کریں گے.اچھی بات کہنا اور معاف کر دینا زیادہ بہتر ہے ایسے صدقہ
سے کہ کوئی آزار اس کے پیچھے آرہا ہو.اور اللہ بے نیاز (اور ) بردبار
ہے.اے لوگو جو ایمان لائے ہو! اپنے صدقات کو احسان جتا کر یا
اذیت دے کر ضائع نہ کیا کرو اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کے
دکھانے کی خاطر خرچ کرتا ہے اور نہ تو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور نہ یوم
آخر پر.پس اس کی مثال ایک ایسی چٹان کی طرح ہے جس پر مٹی ( کی
تہ ) ہو پھر اس پر موسلا دھار بارش برسے تو اسے چٹیل چھوڑ جائے.جو
کچھ وہ کماتے ہیں اس میں سے کسی چیز پر وہ کوئی اختیار نہیں رکھتے.اور
اللہ کا فرقوم کو ہدایت نہیں دیتا.اسی طرح قرآن کریم فرماتا ہے:
وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ
(سورۃ الضحی آیت ۱۱)
ترجمہ.اور جہاں تک سوالی کا تعلق ہے تو اسے مت جھڑک.بھیک مانگنا
اسلام بھکاری کے ساتھ بھی عزت سے پیش آنے کی تلقین کرتا ہے اور درشتی سے
بات کرنے کی سخت ممانعت فرماتا ہے.اگر چہ بھیک مانگنے کو پسند نہیں کیا گیا بلکہ اس
کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے لیکن اشد ضرورت کے وقت مانگنے کے حق کو بھی قائم رکھا گیا
ہے اور کسی شخص کو ایسے مانگنے والوں کی عزت نفس کو مجروح کرنے کی اجازت نہیں
172
Page 185
دی گئی ہے جو بے چارے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہوں.اسلام کے ابتدائی دور میں باوجود اس کے کہ مانگنے والوں کی عزت نفس پوری
طرح محفوظ تھی پھر بھی وہ لوگ خوب اچھی طرح سمجھتے تھے کہ سوال نہ کرنا سوال کرنے
سے بہتر ہے.ایک مرتبہ آنحضرت ﷺ نے مانگنے والے اور دینے والے میں
موازنہ کرتے ہوئے فرمایا اَلْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ السُّفْلی یعنی دینے والا ہاتھ
لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے.اس تعلیم کا نتیجہ تھا کہ بعض مسلمانوں نے غربت میں
مرنا قبول کر لیا مگر زندہ رہنے کے لئے بھیک مانگنا پسند نہ کیا.ایسے لوگوں کی
ضروریات پوری کرنے کے لئے جو اللہ تعالیٰ کے راستہ میں جہاد میں مصروف ہیں
اور غربت کے ہاتھوں بے بس ہیں قرآن کریم نے سارے معاشرہ کو تو جہ دلائی ہے.چنانچہ فرمایا:
لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْصِرُوا فِي سَبِيْلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ
- وو و
ہ ووہ
يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيْمُهُمْ لَا يَسْتَلُونَ النَّاسَ
°
ج
280
الْحَافًا ، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (سورة البقرة آیت ۲۷۴)
ترجمہ.( یہ خرچ ) ان ضرورت مندوں کی خاطر ہے جو اللہ کی راہ میں
محصور کر دیئے گئے (اور) وہ زمین میں چلنے پھرنے کی طاقت نہیں
رکھتے.ایک لاعلم (ان کے) سوال سے بچنے ( کی عادت ) کی وجہ سے
انہیں متمول سمجھتا ہے (لیکن) تو ان کے آثار سے ان کو پہچانتا ہے.وہ
پیچھے پڑ کر لوگوں سے نہیں مانگتے اور جو کچھ بھی تم مال میں سے خرچ کرو تو
اللہ اس کو خوب جانتا ہے.اس امر کی مزید وضاحت مندرجہ ذیل آیت سے ہو جاتی ہے.مَا آفَاءَ اللهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى
173
Page 186
وَالْيَتَمَى وَالْمَسْكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ
ووه و
وَمَا الكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ، وَمَا نَهَكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
شَدِيدُ الْعِقَابِ
( سورة الحشر آیت (۸)
ترجمہ :.اللہ نے بعض بستیوں کے باشندوں کے اموال میں سے )
اپنے رسول کو جو بطور غنیمت عطا کیا ہے تو وہ اللہ کے لئے اور رسول کے
لئے ہے اور اقرباء یتامیٰ اور مسکینوں اور مسافروں کے لئے تا ایسا نہ ہو
کہ یہ ( مال غنیمت ) تمہارے امراء ہی کے دائرہ میں چکر لگاتا رہے.اور رسول جو تمہیں عطا کرے تو اسے لے لو اور جس سے تمہیں رو کے اس
سے رُک جاؤ اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرو.یقیناً اللہ سزا دینے میں سخت
ہے.ط
پیارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفی ﷺ نے ایک حدیث میں بھی اس اصول
کا ذکر فرمایا ہے.اس حدیث کا متعلقہ حصہ درج ذیل ہے:
عَنْ
ـكِيْمِ بْنِ حِرَامٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمَّ قَالَ:
° -
Jo -
الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَابْدَأَ بِمَنْ تَعُولُ وَ خَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ
ده
--٥ -٥ -٥
غِنِّى وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعْفِهِ اللَّهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ
(صحيح البخاري ، كتاب الزكاة ـ باب لاصدقة الأعن ظهر غني)
ترجمہ:.حضرت حکیم بن حزام بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا
اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے.یعنی وہ شخص جو صدقہ و خیرات دیتا ہے
وہ لینے والے سے بہتر ہے.انسان کو چاہئے کہ وہ سب سے پہلے اپنے عیال پر خرچ
کرے.بہترین صدقہ وہ ہے جو ایک دولت مند انسان اپنے اخراجات کے بعد بچی
ہوئی دولت میں سے دیتا ہے.جو کوئی دوسرے کے آگے سوال کرنے سے بچتا ہے
اللہ اسے دے گا اور دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے محفوظ رکھے گا.جو کوئی غنا
174
Page 187
ظاہر کرتا ہے اللہ اسے واقعی غنی بنا دے گا.اس حدیث میں آنحضرت ﷺ یہ نصیحت فرما رہے ہیں کہ تم اوپر والا ہاتھ بن
جاؤ یعنی صدقہ و خیرات کرو اور دوسروں کی خدمت کرو نہ یہ کہ لوگ تم پر احسانات
کریں اور تم صدقات لینے والے بن جاؤ.مالی قربانی کے لئے طیب مال کی شرط
صدقہ و خیرات کے آداب کے علاوہ یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ آپ کیا چیز
خرچ کر رہے ہیں.اگر آپ کوئی ایسی چیز صدقہ کرتے ہیں جو اگر آپ کو دی جائے
اور آپ اسے قبول کرتے وقت شرمندگی محسوس کریں تو آپ کا صدقہ دراصل صدقہ
نہیں ہے.قرآن کریم کے نزدیک یہ تو کسی چیز کو کوڑے میں پھینک دینے کے
مترادف ہے.چنانچہ فرمایا:.ص
%0--0-0-
يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَتِ مَا كَسَبْتُمْ وَ مِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
س وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِذِيْهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ.وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيده
( سورة البقرة آیت ۲۶۸)
ترجمہ.اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو! جو کچھ تم کماتے ہو اس میں سے
اور اس میں سے بھی جو ہم نے تمہارے لئے زمین میں سے نکالا ہے
پاکیزہ چیزیں خرچ کرو.اور (اللہ کی راہ میں) خرچ کرتے وقت اس
میں سے ایسی ناپاک چیز کا قصد نہ کیا کرو کہ تم اسے ہرگز قبول کرنے
والے نہ ہو سوائے اس کے کہ تم (سیکی کے خیال سے) اس سے
طَرْفِ نظر کرو.اور جان لو کہ اللہ بے نیاز (اور ) بہت قابل تعریف
ہے.ط
175
Page 188
لَنْ يَنَالَ اللهَ لُحُومُهَا وَلا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ
( سورۃ الحج آیت ۳۸)
ترجمہ.ہرگز اللہ تک نہ ان کے گوشت پہنچیں گے اور نہ ان کے خون لیکن
تمہارا تقویٰ اس تک پہنچے گا.خدا کے راستہ میں اعلانیہ اور پوشیدہ خرچ
اسلام اللہ تعالیٰ کے راستہ میں پوشیدہ اور علانیہ دونوں طرح سے خرچ کرنے کی
اجازت دیتا ہے.قرآن کریم فرماتا ہے.وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَّفَقَةِ أَوْنَذَرْتُمْ مِنْ نَّذْرِ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ
ووه.أَنْصَارِهِ إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَتِ فَنِعِمَّا هِيَ ، وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ
لَّكُمْ ، وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِّن سَيِّاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ
( سورۃ البقرۃ آیات ۲۷۱.۲۷۲)
ترجمہ.اور جو بھی تم قابل خرچ چیزوں میں سے خرچ کرو یا منتوں میں
سے کوئی منت مانو تو یقیناً اللہ اسے جانتا ہے اور ظالموں کیلئے کوئی مددگار
نہیں.تم اگر صدقات کو ظاہر کرو تو یہ بھی عمدہ بات ہے.اور اگر تم انہیں
چھپاؤ اور انہیں حاجت مندوں کو دو تو یہ تمہارے لئے بہتر ہے.اور وہ
(اللہ ) تمہاری بہت سی برائیاں تم سے دور کر دے گا.اور اللہ اس سے
ہمیشہ باخبر رہتا ہے جو تم کرتے ہو.معاشرتی ذمہ داریاں
اسلامی تعلیم کے مطابق صاحب اختیار لوگوں کے لئے از حد ضروری ہے کہ انہیں
176
Page 189
عوام الناس کی فلاح و بہبود کا اس قدر احساس ہو کہ مطالبات منوانے کے لئے کسی قسم
کے پریشر گروپس بنانے کی ضرورت ہی نہ رہے.قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق
حکمران اپنی رعایا کے حالات کا ذمہ دار اور خدا کے سامنے جوابدہ ہے.صلى الله
آنحضرت ﷺ نے ایک حدیث میں فرمایا ہے.كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
(صحيح ال
ح البخارى كتاب النكاح باب المرأه راعية في بيت زوجها)
ترجمہ :.تم میں سے ہر کوئی ایک چرواہے کی مانند ہے.(وہ بھیڑوں کا
مالک تو نہیں لیکن جو بھیڑیں وہ چرا رہا ہے ان کی دیکھ بھال کی
ذمہ داری اسے دی گئی ہے ) اور تم سب اپنی ذمہ داری کے بارہ میں
جوابدہ ہو.اس حدیث میں ایسے کئی قسم کے تعلقات کا ذکر ہے جن کے باعث ایک انسان
کسی دوسرے انسان کا ذمہ دار بن جاتا ہے.مثال کے طور پر آقا اپنے غلام کا
ذمہ دار ہے.خاوند اور بیوی دونوں اپنے خاندان کے ذمہ دار ہیں.خاوند خاندان
کے سربراہ کے طور پر اور بیوی گھر کا انتظام چلانے کے لحاظ سے.اسی طرح ایک
آجر اپنے اجیر کا ذمہ دار ہے.على هذا القیاس.ان سب تعلقات کا ذکر کرتے ہوئے
آنحضرت ﷺ نے بار بار فرمایا کہ یاد رکھو تم ذمہ دار بنائے گئے ہو اور اپنی اس
ذمہ داری کے متعلق جوابدہ ہو.تاریخ اسلام کا ایک واقعہ
ایک رات حضرت عمر مدینہ کی ایک نواحی بستی کی ایک گلی میں سے گزر رہے
تھے.آپ کا یہ معمول تھا کہ براہ راست اپنی رعایا کے حالات معلوم کرنے کے لئے
177
Page 190
بھیس بدل کر گلیوں میں چکر لگایا کرتے تھے.آپ کو ایک گھر سے بچوں کے رونے
کی آواز میں آئیں.ایسا لگتا تھا کہ بچے کسی تکلیف میں ہیں.پوچھنے پر پتہ چلا کہ
ایک ماں اور اس کے تین چار بچے چولہے کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں.چولہے پر
ہنڈیا رکھی ہے جس میں کوئی چیز اُبل رہی ہے.حضرت عمر نے ماں سے پوچھا کہ کیا
بات ہے، بچے کیوں رو رہے ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ بچے بھوکے ہیں اور میرے
پاس انہیں کھلانے کے لئے کچھ نہیں.میں نے انہیں بہلانے کی خاطر ہنڈیا میں کچھ
پانی اور پتھر ڈال کر چولہے پر رکھا ہوا ہے تا کہ وہ یہ سمجھیں کہ کھانا تیار ہو رہا ہے.یہ
سن کر حضرت عمرؓ بڑے کرب اور اضطراب کی حالت میں فوراً واپس دربار خلافت
میں تشریف لائے.آپ نے کچھ آٹا، گوشت اور کھجوریں لیں، انہیں ایک بوری میں
رکھا اور قریب کھڑے ہوئے غلام سے کہا کہ اسے میری کمر پر رکھ دو.غلام نے
حیرت سے کہا کہ امیر المومنین! آپ کیوں تکلیف فرماتے ہیں یہ بوجھ مجھے اٹھانے
دیں.حضرت عمر نے فرمایا بے شک آج تو تم میرا بوجھ اٹھا سکتے ہولیکن قیامت کے
دن میرا بوجھ کون اٹھائے گا؟ آپ کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جزا سزا کے دن کوئی
اور اس امر کا جوابدہ نہیں ہو گا کہ عمر نے اپنی ذمہ داریوں کو کس طرح ادا کیا تھا اس
لئے انہیں اپنا بوجھ خود ہی اٹھانا ہو گا.یہ دراصل نفس کے لئے ایک قسم کی سزا تھی جو
حضرت عمرؓ نے اپنے لئے تجویز فرمائی.آپ نے محسوس کیا کہ اس غریب اور بے کس
عورت اور اس کے بچوں کی جس حالت زار کو دیکھ کر آئے ہیں اس کی ذمہ داری
آپ پر عائد ہوتی ہے.در حقیقت آپ کو شدت سے اس امر کا احساس تھا کہ سارے
شہر اور اس کے معاملات کے آخری ذمہ دار آپ ہی ہیں اور یہ ذمہ داری آپ ہی کو
ادا کرنی ہے.اگر چہ ہر سر براہ مملکت کے لئے یہ ناممکن ہے کہ وہ حضرت عمر کی برابری
کر سکے لیکن کیا بلحاظ سوچ اور کیا بلحاظ عمل آپ کا مثالی کردار ہمیشہ کے لئے ماڈل اور
178
Page 191
نمونے کا کام دیتا رہے گا.دراصل یہی وہ روح ہے جسے عصر حاضر کے تمام
معاشروں میں زندہ کرنے کی ضرورت ہے.اگر حکومتیں لوگوں کی فلاح و بہبود کا
خیال رکھیں اور ان کی تکالیف اور دکھ درد کا احساس پیدا کریں تو قبل اس کے کہ لوگ
اپنی تکالیف اور محرومیوں کے اظہار کے لئے اٹھ کھڑے ہوں ارباب اختیار خود اپنے
طور پر ان کے دکھ و درد کا مداوا کرنے پر مجبور ہو جائیں گے.وہ اصلاح احوال کی
کوشش لوگوں کے مطالبات یا کسی خوف کی وجہ سے نہیں کریں گے بلکہ خود ان کے
اپنے ضمیر کی آواز انہیں ایسا کرنے پر مجبور کر دے گی.خدا کی عطا کردہ سب نعمتوں میں سے خرچ کرنا
قرآن کریم نے انفاق فی سبیل اللہ کو صرف مال کے خرچ تک محدود نہیں رکھا
بلکہ اس کے مفہوم کو انتہائی وسیع کر دیا ہے.ایک بے مثال آیت جسے قرآن کریم نے
بار بار دہرایا ہے یہ ہے.ومما رزقنهم ينفقون
( سورة البقرة آیت ۴)
ترجمہ:.اور جو کچھ ہم انہیں رزق دیتے ہیں وہ اس میں سے خرچ کرتے
ہیں.اللہ کی عطا کردہ نعمتوں میں ہر قسم کی مادی نعماء کے علاوہ تمام استعدادیں،
صلاحیتیں ، خوبیاں اور قومی نیز انسانی تعلقات وغیرہ شامل ہیں.اس مختصر سے جملہ
میں عزت، امن اور آرام وغیرہ جیسی نعمتیں بھی آ جاتی ہیں.غرضیکہ ہر وہ چیز جو تصور
میں آ سکتی ہے وَ مِمَّا رَزَقْنَهُمْ میں شامل ہے.مسن کا لفظ بھی یہاں بڑی خوبصورتی سے استعمال ہوا ہے جس کے لفظی معنی ” بعض
اور ” کچھ“ کے ہیں.اس لفظ کے استعمال سے آیت میں موجود نصیحت پر عمل کرنا ہر
179
Page 192
"
ایک کے لئے ممکن ہو گیا ہے.وَ مِمَّا رَزَقْنَهُمْ کے یہ معنی نہیں کہ وہ سب کچھ جو ہم
نے انہیں دیا ہے اللہ کے راستہ میں خرچ کرتے ہیں بلکہ اس کے معنی ہیں کہ جو کچھ
بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ اس میں سے کچھ خرچ کرتے ہیں اور لفظ ” کچھ میں
اتنی لچک اور وسعت ہے کہ عام لوگ بھی جو بڑی بڑی قربانیوں کی طاقت نہیں رکھتے
وہ کم از کم اپنی حیثیت کے مطابق انفاق فی سبیل اللہ میں حصہ لے سکتے ہیں.خدمت
خلق کا یہ وہ ماحول ہے جس کے قیام اور فروغ کے لئے اسلام کوشش کرتا ہے.اس
ماحول کا تعلق ایک طرف تو فرد کے سماجی رویوں اور اس کے معاشرتی طرز عمل سے
ہے اور دوسری طرف اس کا تعلق اس کی اقتصادی و معاشی سرگرمیوں سے ہے.ایک ایسا معاشی نظام جس میں شامل ہر فرد کو ذاتی ملکیت کا ہی غم کھائے جا رہا ہو
اور وہ دونوں ہاتھوں سے سمیٹنے کی تگ و دو میں مصروف ہو وہاں صحیح اور غلط جائز اور
ناجائز میں فرق کرنا بڑا مشکل بلکہ عملاً ناممکن ہو جاتا ہے.غالب امکان ہے کہ ایسا
معاشرہ اپنی حدود میں رہنے کی بجائے دوسروں کے حقوق میں ناجائز دخل اندازی کا
مرتکب ہو گا.لیکن دوسری طرف جس معاشرہ کے افراد کو ہمیشہ یہ یاد دلایا جائے اور
تربیت بھی دی جائے کہ وہ دوسروں کو ان کے حق سے زیادہ دیا کریں ان سے ہرگز
یہ توقع نہیں کی جاسکتی کہ وہ دوسروں کے حقوق غصب کرنا شروع کر دیں گے.ایسے
ماحول میں بھلا کسی کے استحصال کا کیا امکان ہوسکتا ہے.خدمت خلق
خدمت خلق کے اسلامی تصور کو اس آیت میں بڑی خوبصورتی اور جامعیت کے
ساتھ بیان کیا گیا ہے.كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ
180
Page 193
تُؤْمِنُونَ بِاللهِ.( سورۃ آل عمران آیت ۱۱۱)
b
ترجمہ تم بہترین امت ہو جو انسانوں کے فائدہ کے لئے نکالی گئی ہو.تم
اچھی باتوں کا حکم دیتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان
لاتے ہو.تمہاری فضیلت اس وقت تک ہے جب تک تم خدمت کرنے والا مزاج رکھتے
ہو.اگر تم خدمت خلق نہیں کرتے تو تمہیں اسلام یا امت مسلمہ کی طرف سے برتری کا
دعویٰ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے.شراب نوشی اور جوئے کی ممانعت
جب نشہ کی بات کی جائے تو ذہن عام طور پر ہیروئین اور کوکین کی طرف منتقل ہو
جاتا ہے.لیکن نشہ کے لفظ کو وسیع تر مفہوم میں لیا جائے تو اس میں شراب نوشی اور جوا
دونوں شامل ہو جاتے ہیں.کیونکہ لذت یابی کے ان ہر دو طریق کو معاشرہ بری نظر
سے نہیں دیکھتا اس لئے انہیں بہت کم نشہ کا نام دیا جاتا ہے حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ
شراب نوشی اور جو ا معاشرہ کی صحت اور سلامتی کے لئے کوئی اچھی علامات نہیں ہیں.دنیا کے ایسے ممالک جہاں جُوئے کا اتنے وسیع پیمانے پر رواج نہیں وہاں بھی تقریباً
ہر سطح پر لوگ چھوٹے بڑے اڈوں کی شکل میں جوئے کے شغل میں ملوث ہیں.دوسرا
بڑا نشہ شراب نوشی ہے جس کا شکار آج دنیا کے مختلف معاشرے ہو چکے ہیں.قرآن کریم نے شراب نوشی اور جو ا دونوں کی ممانعت فرمائی ہے.فرمایا:
يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ
الشَّيْطَنِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَنُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُم
ه و
M016-0 mo
الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَن الصَّلوة.ج
181
Page 194
°
ه شه وه
فهل انتم منتهون
( سورة المائدة آیات ۹۱ - ۹۲)
ترجمہ :.اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو! یقیناً مدہوش کرنے والی چیز اور
جوا اور بت ( پرستی) اور تیروں سے قسمت آزمائی یہ سب نا پاک شیطانی
عمل ہیں.پس ان سے پوری طرح بچو تا تم کامیاب ہو جاؤ.یقیناً
شیطان چاہتا ہے کہ نشہ اور جوئے کے دوران تمہارے درمیان بغض اور
عناد پیدا کر دے اور تمہیں ذکر الہی اور نماز سے باز رکھے.تو کیا تم باز
آ جانے والے ہو.حضرت رسول کریم ﷺ نے شراب نوشی کو اُمّ الخبائث یعنی تمام برائیوں کی
ماں قرار دیا ہے.شراب اور جوئے کی عادت ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے چکی
ہے.اس لحاظ سے مختلف خطوں اور علاقوں میں کوئی فرق باقی نہیں رہا.سیاست کی
دنیا میں تو شاید مشرق و مغرب کبھی متحد نہ ہو سکیں لیکن جہاں تک شراب نوشی اور
جوا بازی کے رجحانات کا تعلق ہے کیا مشرق اور کیا مغرب اور کیا شمال اور کیا جنوب
سب اکٹھے ہو چکے ہیں.شراب نوشی اور جُوا دونوں ہی معاشرتی برائیاں ہیں.برطانیہ میں شراب نوشی پر
ایک دن میں جتنا خرچ ہوتا ہے اس سے افریقہ کے لاکھوں قحط زدہ لوگوں کا کئی
ہفتوں تک پیٹ بھرا جا سکتا ہے.مگر ستم یہ ہے کہ افریقہ اور دیگر براعظموں کے غریب
ترین ممالک میں بھی شراب نوشی کو ایک ایسی عیاشی نہیں سمجھا جاتا جس کے لوگ متحمل
نہ ہوسکیں.افریقہ کے لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو نہ تو زندگی کی بنیادی ضروریات
پوری کر سکتے ہیں اور نہ اپنے بچوں کو تعلیم دلا سکتے ہیں مگر پینے کے لئے کسی نہ کسی
طرح شراب ضرور حاصل کر لیتے ہیں.جنوبی ہندوستان کے پسماندہ علاقوں میں
جہاں فیکٹریوں کی تیار شدہ شراب خریدنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں وہاں اس کی
182
Page 195
بجائے خانہ ساز ” ٹوڈی“ سے گزارہ کر لیا جاتا ہے.اگر چہ غربت اس ام الخبائث کو
پھیلنے سے کسی حد تک روکتی ضرور ہے لیکن جونہی فی کس آمدنی بڑھتی ہے شراب پر
اٹھنے والے خرچ میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے.عجیب بات یہ ہے کہ جب تک کوئی شخص
حد سے زیادہ شراب پینے کا عادی نہ ہو جائے اور نشہ میں دھت نالیوں میں گرا پڑا نظر
نہ آئے شراب نوشی کی عادت کو برا نہیں سمجھا جاتا.یہ سوال اٹھایا جا سکتا ہے کہ شراب نوشی اور جوئے کو عصر حاضر کے مسائل کے
طور پر کیوں لیا جائے جبکہ یہ دونوں نشے تو ہمیشہ سے ہر جگہ تاریخ انسانی کا حصہ رہے
ہیں.بلاشبہ اس لحاظ سے یہ صرف اس دور کا مسئلہ ہی نہیں ہے بلکہ اسے تاریخ عالم
کے ہر دور کا ایک دائمی مسئلہ کہا جانا چاہئے.اقتصادیات کے نقطہ نگاہ سے شراب نوشی کی نسبت جوا زیادہ قابل اعتراض ٹھہرتا
ہے.جوئے میں اقتصادی لحاظ سے پیداوار میں کسی اضافہ کے بغیر دولت ایک ہاتھ
سے نکل کر دوسرے ہاتھ میں چلی جاتی ہے.یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے سٹے کے
کاروبار میں اجناس کے تبادلہ کے بغیر دولت کا دولت سے تبادلہ ہوتا ہے.جوئے
میں سرمایہ اقتصادی ترقی اور دولت کی پیداوار کے عمل میں کسی قسم کا حصہ لئے بغیر
ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں چلا جاتا ہے.منی مارکیٹس (Money Markets)
یعنی بازار حصص تو پھر بھی کسی نہ کسی حد تک اقتصادی اغراض و مقاصد کو پورا کرتے
ہیں لیکن اقتصادی لحاظ سے جو ایک بالکل بے مقصد عمل ہے جب کہ آزاد تجارت اور
صنعتی ماحول میں دولت کا تبادلہ اقتصادیات کو مادی فائدہ پہنچاتا ہے.قدر (Value) کے تبادلہ میں بالعموم فریقین کو فائدہ ہوتا ہے.یہ بات نا قابل فہم
ہے کہ تاجروں کی اکثریت کو نقصان اٹھانا پڑے.جب کہ یہ بات بہر حال طے ہے
کہ جوئے میں ایک بہت بڑی اکثریت کو اکثر نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے.لیکن
183
Page 196
تجربہ شاہد ہے کہ قمار خانے بالعموم مالی تباہی کا شکار نہیں ہوتے.پس جوئے میں
صرف چند لوگوں کے نفع کی خاطر لاکھوں لوگ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں.اپنی دولت
لٹا کر انہیں صرف ایک ہیجانی لذت حاصل ہوتی ہے.بازی جیتنے کی امید یا ہارنے
کے خوف کے درمیان بے یقینی کی وہ ہیجانی کیفیت اس وقت دم توڑ دیتی ہے جب
انہیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ہار گئے ہیں.اپنی ہاری ہوئی رقم واپس لینے کی موہوم سی امید
لئے ہوئے وہ پھر اپنا مال داؤ پر لگاتے ہیں یہاں تک کہ ان کی پریشانی اور ذہنی دباؤ
اس ہیجانی لذت سے بہت بڑھ جاتا ہے جو اس سارے کا روبار میں انہیں حاصل ہوئی
تھی.اس ناکامی کے نتیجہ میں وہ شدید غم و غصہ اور ذہنی تناؤ کا شکار ہو جاتے ہیں جو
ان کی ذات تک ہی محدود نہیں رہتا بلکہ اس کا اظہار رشتہ داروں پر بھی ہونے لگتا
ہے.معاشرہ کے غریب طبقات میں افراد خانہ کی روز مرہ کی ضروریات تک جوئے
کی نذر ہو جاتی ہیں.قرآن کریم نے شراب نوشی اور جوئے کی ممانعت کا ذکر کرتے
ہوئے تسلیم کیا ہے کہ یقیناً ان سے بعض جزوی فائدے اٹھائے جا سکتے ہیں.مگر یہ بات
طے شدہ ہے کہ ان کے نقصانات ان کے جزوی فوائد کے مقابلہ میں بہت زیادہ ہیں.يَسْتَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْم كَبِيرٌ وَ مَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَ
ه
إِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا وَ يَسْتَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ
الله لَكُمُ الْآيَتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ
(سورة البقرة آیت ۲۲۰)
ترجمہ.وہ تجھ سے شراب اور جوئے کے متعلق سوال کرتے ہیں.تو کہہ
دے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ (بھی) ہے اور لوگوں کے لئے فوائد
بھی.اور دونوں کا گناہ ( کا پہلو ) ان کے فائدہ سے بڑھ کر ہے.اور
وہ تجھ سے (یہ بھی) پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں؟ ان سے کہہ دے
کہ (ضروریات میں سے ) جو بھی بچتا ہے.اسی طرح اللہ تمہارے لئے
(اپنے) نشانات کھول کھول کر بیان کرتا ہے تا کہ تم تفکر کرو.184
Page 197
یہ بحث اٹھائی جا سکتی ہے کہ جس نے دولت کمائی ہے وہ جیسے چاہے اس کے
ذریعہ لذت حاصل کرے کسی دوسرے شخص کو اس میں دخل اندازی کا کیا حق پہنچتا
ہے.جیسے کوئی خوش ہوتا ہے اسے ہونے دیں.معاشرہ کو فرد کی آزادی میں اس
حد تک دخل اندازی کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اسے یہ بتائے کہ وہ اپنی کمائی ہوئی
دولت کو کہاں اور کیسے خرچ کرے.لیکن یہ یاد رکھنا چاہئے کہ مذہبی تعلیم کا اکثر
حصہ وعظ ونصیحت اور تنبیہ کے انداز میں ہوتا ہے.دنیا کی زندگی تک کسی مذہب کی
تعلیم میں بھی کوئی جبر شامل نہیں ہے سوائے اس کے کہ کوئی دوسرے کے خلاف جرم کا
ارتکاب کرے اور جرائم سے مراد بھی وہ جرائم ہیں جو غیر مذہبی نقطہ نظر سے بھی
قابل دست اندازی ہیں مثلاً قتل، چوری، دھوکہ دہی ، بدعنوانی ، حق تلفی وغیرہ.مگر
مذاہب کے نزدیک ان کے علاوہ بھی ایسے سماجی جرائم ہیں جو بحیثیت مجموعی سارے
معاشرہ کے لئے سخت نقصان دہ ہیں.ان جرائم کی سزا افراد کو تو نہیں دی جاتی مگر ان
کے نتیجہ میں سارا معاشرہ سزا بھگتا ہے.اور یہ سزا دراصل وسیع تر معاشرتی قوانین
کے ذریعہ ملتی ہے.یہ کوئی حیران کن بات نہیں کہ شراب نوشی اور جوئے کی بد عادات
میں مبتلا افراد بہت جلد سارے معاشرہ کے لئے ایک مصیبت بن جاتے ہیں.یہاں
تک کہ پھر سارا معاشرہ ہی اس قابل نہیں رہتا کہ وہ اپنے اخراجات پورے کر سکے.قومی دولت کا ایک بڑا حصہ مسلسل ضائع ہوتا چلا جاتا ہے.ایسے ماحول میں لوگوں کی مایوسیاں اور ناکامیاں بھی بڑھتی چلی جاتی ہیں.جوئے اور شراب نوشی کے ساتھ جرائم میں بھی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے.عائلی زندگی کا
سکون برباد ہو جاتا ہے.ایسے گھروں کے دکھ شراب نوشی کا بالواسطہ نتیجہ ہیں جو ہمیشہ
بڑھتے چلے جاتے ہیں.کئی گھر براہ راست شراب نوشی اور جوئے بازی کی نذر
ہو جاتے ہیں اور کتنے ہی ازدواجی بندھن ان عادات کی وجہ سے ٹوٹ جاتے ہیں.185
Page 198
اقتصادی اور سماجی لحاظ سے شراب نوشی کے بد نتائج کی نشان دہی مشہور رسالہ
سائنٹفک امیریکن (Scientific American) میں بھی کی گئی ہے.ان میں
گھریلو تشدد کے علاوہ بچوں کے ساتھ جنسی جرائم ماؤں اور بہنوں کے ساتھ بدکاری
اور زنا وغیرہ قسم کے رزائل شامل ہیں.یہ تمام گھناؤنے جرائم شراب کے نشہ میں ہر
قسم کی تمیز اٹھ جانے کی وجہ سے ہوتے ہیں.مذکورہ بالا رسالہ نے شراب نوشی کے
نقصانات کے متعلق کچھ اعداد و شمار بھی دیئے ہیں جو پیش کئے جا رہے ہیں.شراب نوشی کے باعث ہونے والی اموات
☆
شراب نوشی کرنے والوں کی عمر دس سال کم ہو جاتی ہے.شراب نوشی کرنے والے مردوں میں شرح اموات عام شرح سے دگنی اور
عورتوں میں عام شرح سے تین گنا زیادہ ہے.شراب پینے والوں میں خود کشی کی شرح عام شرح موت سے چھ گنا زیادہ ہے.پچیس سے چوالیس سال کی عمر کے مردوں میں موت کی چار بڑی وجوہات
میں شراب نوشی کا بڑا عمل دخل ہے.اول حادثات جن میں پچاس فیصد حادثات
شراب نوشی کی وجہ سے ہوتے ہیں.دوم قتل جن میں سے ساٹھ فیصد قتل شراب نوشی
کے زیر اثر ہوتے ہیں.سوم خود کشی چہارم جگر کی بیماریاں.شراب نوشی کے باعث ہونے والے سالانہ اقتصادی نقصانات
پیداواری ضیاع
صحت پر اٹھنے والے اخراجات
186
۱۴ اعشاریہ 9 بلین ڈالر
۸ اعشاریہ 3 بلین ڈالر
Page 199
حادثات میں مالی نقصانات
آگ لگنے سے ہونے والے نقصانات
پر تشدد جرائم سے ہونے والے نقصانات
۴ اعشاریہ سے بلین ڈالر
• اعشاریہ 3 بلین ڈالر
۱ اعشاریہ ۵ بلین ڈالر
جرائم کے نتیجہ میں معاشرہ کے رد عمل پر اٹھنے والے اخراجات ۱ اعشاریہ 9 بلین ڈالر
شراب نوشی سے ہونے والے کل نقصانات
۳۱ اعشاریہ 4 بلین ڈالر
شراب نوشی ، جوئے بازی، موسیقی اور رقص جیسے عیش وعشرت کے ذرائع کو اکثر
معاشروں میں بے ضرر سمجھا جاتا ہے.انہیں مختلف ثقافتوں کا جزو لاینفک قرار دیا جاتا
ہے.اگر چہ مختلف معاشروں میں ان کی مختلف شکلیں ہیں مگر ان مشاغل کے بنیادی
خدوخال ایک جیسے ہی ہیں.مصوری، مجسمہ سازی اور اس قسم کے دیگر چند مشاغل کو
چھوڑ کر باقی مشاغل زیادہ دیر تک ثقافت کا بے ضرر حصہ نہیں رہتے بلکہ ایک ایسا بوجھ
بن جاتے ہیں جس سے معاشرہ کی کمر ٹوٹ جاتی ہے.معاشرہ خود اپنے رجحانات کا
رخ متعین کرنے کے قابل نہیں رہتا.شراب نوشی، جوئے بازی، موسیقی اور رقص
وغیرہ کی طرف لوگ کھنچے چلے جاتے ہیں.نوجوان طبقہ بڑی تیزی سے ان سرگرمیوں
کا شکار ہوتا ہے.ایک بھیڑ چال شروع ہو جاتی ہے اور ان مشاغل میں دلچپسی ایک
جنون کی شکل اختیار کر لیتی ہے.اگر کوئی شخص ایسے معاشروں کو دیکھے تو شاید وہ یہ
سمجھے کہ نعوذ باللہ انسانی پیدائش کی غرض وغایت ہی ایسی بے سود لذتوں کا پیچھا کرنا
اور سفلی خواہشات کا غلام بن جانا ہے.مگر قرآن کریم نے پیدائش انسانی کا یہ مقصد
قرار نہیں دیا بلکہ فرماتا ہے:
إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَايَتِ لِأُولِى
الألْبَاب الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ فِيمَا وَقُعُودًا وَّ عَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي
خَلْقَ السَّمواتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذا بَاطِلاً سُبْحَنَكَ فَقِنَا عَذَابَ
( سورة آل عمران آیات ۱۹۱ ۱۹۲)
النَّارِه
187
Page 200
ترجمہ:.یقیناً آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے
ادلنے بدلنے میں صاحب عقل لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں.وہ لوگ جو
اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہوئے بھی اور بیٹھے ہوئے بھی اور اپنے
پہلوؤں کے بل بھی اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر
کرتے رہتے ہیں (اور بے ساختہ کہتے ہیں ) اے ہمارے رب ! تو نے
ہرگز یہ بے مقصد پیدا نہیں کیا.پاک ہے تو.پس ہمیں آگ کے عذاب
سے بچا.اللہ تعالیٰ کے عقل مند بندوں کی صفات کے متعلق قرآن کریم یہ اعلان کرتا ہے
کہ وہ تخلیق حیات کے عقیدہ پر خوب غور و فکر کے بعد بے اختیار پکار اٹھتے ہیں کہ یہ
کائنات اور اس کی تخلیق بے مقصد نہیں ہو سکتی.قرآن کریم کی یہ آیات ارشمیدس
کے اس اظہار مسرت کی یاد دلاتی ہیں جب ایک انکشاف پر اس نے Eureka
یعنی ” میں نے پالیا“ کا نعرہ بلند کیا تھا.پس اسلام کا پیش کردہ معاشرتی ماحول مادہ پرستی کے ماحول سے بالکل مختلف
ہے.قرآن کریم فرماتا ہے کہ انسان کی پیدائش کا اعلیٰ مقصد اس راستہ پر گامزن ہونا
ہے جو خالق تک پہنچاتا ہے.عبادت کے انہی وسیع معنوں میں قرآن کریم یہ اعلان
فرماتا ہے کہ
وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ (سورۃ الذاریات آیت ۵۷)
ترجمہ:.اور میں نے جن و انس کو پیدا نہیں کیا مگر اس غرض سے کہ وہ
میری عبادت کریں.عیش وعشرت کے مختلف ذرائع کا جائزہ لیں تو شاید کسی کو ان میں بظاہر کوئی ایسی
مضرت نظر نہ آئے جسے ان مشاغل پر مکمل پابندی کا جواز بنایا جا سکے خصوصاً
مادر پدر آزاد لوگوں کے معاشرہ میں یہ سمجھنا بے حد مشکل ہے کہ اسلام اس بارہ میں
188
Page 201
اس حد تک سخت کیوں ہے؟ یہاں تک کہ بعض کے نزدیک اسلام ایک خشک مذہب
ہے.حقیقت یہ ہے کہ اسلام ہرگز ایک خشک مذہب نہیں ہے لیکن اگر اسے دور سے
دیکھا جائے اور پوری طرح سمجھا نہ جائے تو ممکن ہے کہ بعض لوگوں کو خشک اور بور
دکھائی دے.سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جن لوگوں میں نیکی کا ذوق پیدا ہو جائے
وہ ان نیک اعمال کے ذریعہ بھی اعلیٰ درجہ کی لذت پا لیتے ہیں جو باہر سے دیکھنے
والے کو بور نظر آتے ہیں.ان سے بھی زیادہ خوش نصیب وہ لوگ ہیں جنہوں نے
محبت الہی کا مزہ چکھ لیا ہو.یہ لوگ روحانیت کے اتنے بلند مقام پر فائز ہوتے ہیں
جہاں سے دنیا کی سفلی لذات بہت حقیر، گھٹیا بے معنی اور عارضی دکھائی دینے لگ
جاتی ہیں.تیسرے یہ کہ وسیع تناظر میں دیکھا جائے تو وہ معاشرہ جس نے
عیش وعشرت کو اپنا معبود نہ بنایا ہو بھی تہی دست نہیں ہوتا.شراب نوشی اور جوئے کی بحث کا آخری اور مختصر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ دراصل ایک
قدر کا دوسری قدر سے تبادلہ ہے.شراب کے نشہ کی ہیجانی کیفیت اور انتہا درجہ کی
جسمانی لذت اور مستی کے عوض حقیقی امن و سکون، طمانیت قلب، احساس تحفظ،
شرافت اور قناعت کبھی کچھ ہاتھ سے جاتا رہتا ہے.حالانکہ یہ چیزیں اپنی ذات میں
اعلیٰ وارفع قدریں ہیں جن سے بڑھ کر کوئی انعام نہیں ہوسکتا.اگر اسلام کے پیش کردہ معاشرتی ماحول کا آج کے معاشرتی اور سماجی ماحول
سے بحیثیت مجموعی موازنہ کیا جائے تو یہ بات بآسانی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ محبت الہی
کا شجر مادہ پرستی کی زمین میں قرار نہیں پکڑ سکتا.جولوگ مادی زندگی کی دلچسپیوں اور
رنگینیوں میں غرق ہو جائیں وہ خدا کی محبت میں کیسے کھو سکتے ہیں اگر چہ کچھ استثنائی
صورتیں ہیں مگر ان سے قانون تو نہیں بنا کرتے.پس خلاصہ یہی ہے کہ اسلام جس
سماجی ماحول کو پیش کرتا ہے وہ مادہ پرستی کے ماحول سے بے حد مختلف ہے.189
Page 203
اقتصادی امن
سرمایہ دارانہ نظام، اشتراکیت اور اسلام کا اقتصادی فلسفہ.....سرمایہ دارانہ نظام....سائینٹیفک سوشلزم
اسلامی نظریہ
سرمایہ دارانہ معاشرہ کی چار خصوصیات....دنیا کا بدلتا ہوا اقتصادی نظام....اسلام کا اقتصادی نظام
زكوة
سود کی ممانعت...برطانیہ میں شرح سود کا مسئلہ
سود کے دیگر نقصانات
سود امن کے لئے ایک خطرہ.....دولت کے انبار لگانے کی ممانعت.....سادہ طرز زندگی
شادی بیاہ کے اخراجات
غرباء کی دعوت قبول کرنا
191
Page 204
کھانے پینے میں اعتدال....قرض کا لین دین..معاشی طبقاتی فرق
حمد...اسلام کا قانون وراثت
رشوت کی ممانعت
تجارتی ضابطہ اخلاق.....بنیادی ضروریات زندگی
عبادت.معاشرتی وحدت کا ایک ذریعہ....عالمی ذمہ داریاں
192
Page 205
b
يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبوا وَيُرْبِي الصَّدَقَتِ * وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارِ أَثِيمٍ
(سورۃ البقرۃ آیت ۲۷۷)
ترجمہ:.اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے اور
اللہ ہر سخت ناشکرے ( اور ) بہت گنہگار کو پسند نہیں کرتا.كَلَّا بَلْ لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ ، وَلَا تَحضُّونَ عَلَى طَعَامِ المِسْكِيْنِ وَ
دو ده
و لگا لیا
تَأكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلا لمَّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حَبَّاجَمَّا
(سورۃ الفجر آیات ۱۸ تا ۲۱)
ترجمہ:.خبر دارا در حقیقت تم یتیم کی عزت نہیں کرتے.اور
نہ ہی مسکین کو کھانا کھلانے کی ایک دوسرے کو ترغیب دیتے
ہو اور تم ورثہ تمام تر ہڑپ کر جاتے ہو اور مال سے بہت
زیادہ محبت کرتے ہو.193
Page 207
سرمایہ دارانہ نظام، اشتراکیت اور اسلام کا اقتصادی فلسفہ
اسلام کے اقتصادی نظام کا سرمایہ دارانہ نظام یا سائینٹیفک سوشلزم سے کوئی تعلق
نہیں ہے.یہ نظام سائنسی تو ہے لیکن بے جا پابندیوں سے آزاد ہے، ذاتی ملکیت
اور نجی کاروبار کی اجازت تو دیتا ہے لیکن لالچ اور حرص کے ہاتھوں ہونے والی
لوٹ کھسوٹ کو بھی روکتا ہے.اسطرح چند لوگوں کے ہاتھ میں دولت کے ایسے ارتکاز
کی حوصلہ شکنی کرتا ہے جس کے نتیجہ میں معاشرہ کا ایک بڑا حصہ ایک ظالم و جابر اور
بے حس استحصالی نظام کے شکنجہ میں پھنس کر رہ جاتا ہے.سرمایہ دارانہ نظام،
اشتراکیت اور اسلام کے اقتصادی فلسفوں میں تین بنیادی فرق ہیں.سرمایہ دارانہ نظام
اس نظام میں سرمایہ کی افزائش سود کے ذریعہ ہوتی ہے.اس میں اصولی طور پر
تسلیم کر لیا گیا ہے کہ سرمائے کو یہ حق حاصل ہے کہ اسے بڑھنے کا موقع دیا جائے.سود ہی کی وجہ سے سرمایہ چند ہاتھوں میں اکٹھا ہو جاتا ہے اور پھر اسی سرمایہ کی قوت
سے پیداواری عمل جاری و ساری رہتا ہے.مختصر یہ کہ سرمائے کو گردش میں رکھنے کا
بنیادی محرک سود ہی ہوتا ہے.سائلینٹیفک سوشلزم
اس نظام میں اگر چہ سود بطور محرک تو موجود نہیں ہے جس سے پیداواری نظام
میں سرمایہ کی گردش ہوتی رہے لیکن یہاں دراصل سرمایہ کاری کے لئے کسی ترغیب کی
ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ سرمایہ پر حکومت کی بلا شرکت غیر اجارہ داری ہوتی ہے.195
Page 208
آزاد نجی کاروبار میں سود ہو یا نہ ہو ذاتی ملکیت کا احساس ہی سرمایہ میں تیزی
سے اضافہ کرنے کی خواہش کو ابھارنے کے لئے کافی ہے.سود پر قرض لینے کی
صورت میں سود کی شرح ہی وہ معیار ہے جس کے ذریعہ ہم یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ
مجموعی قومی سرمایہ میں کمی ہوئی ہے یا اضافہ ہوا ہے مگر سوشلزم کے اقتصادی نظام میں
اول تو سرمایہ میں اضافہ کی کوئی خواہش ہی نہیں ہوتی کیونکہ اس میں کسی کا ذاتی
سرمایہ نہیں ہوتا دوسرے اس میں کوئی ایسا طریق موجود نہیں ہے جس کے ذریعہ یہ
معلوم کیا جا سکے کہ سرمایہ میں اضافہ کی شرح اقتصادی لحاظ سے کافی بھی ہے یا نہیں.سوشلزم میں چونکہ حکومت سارے ملکی سرمایہ کو جبراً اپنے قبضہ میں لے لیتی ہے اس
لئے وہاں سودی نظام کی بات بالکل بے معنی اور غیر متعلق ہو کر رہ جاتی ہے.مشکل یہ
ہے کہ جب کسی پر دباؤ نہ ہو کہ اس نے سود میں ادا کی جانے والی رقم سے زیادہ کمانا
ہے تو پھر کوئی ترغیب باقی نہیں رہتی اور احساس ذمہ داری ختم ہو جاتا ہے.اگر ایک اشترا کی ریاست میں سارے زیر گردش سرمایہ کی اس نقطہ نظر سے قیمت
لگائی جائے کہ اس سرمایہ کو بینک میں رکھنے سے کتنا سودمل سکتا ہے تو ہمیں اس طرح
تصویر کا صرف ایک رخ دکھائی دے گا.دوسرے رخ کو سمجھنے کے لئے ملکی اقتصادیات کا
نفع و نقصان کی بنیاد پر اندازہ کرنا پڑے گا.یہ حساب کرنا اگر چہ اتنا آسان نہیں ہے
کیونکہ اس میں کئی پیچیدگیاں ہیں مثلاً ملازمین کی اجرت کا اندازہ کرنا وغیرہ لیکن اگر
ماہرین سر جوڑ کر بیٹھیں تو یہ پیچیدگیاں دور ہو سکتی ہیں.تصویر کے دونوں رخ دیکھنے سے
اور ان کے باہمی موازنہ سے بعض بڑے دلچسپ امکانات ہمارے سامنے آئیں گے.بہت ممکن ہے کہ اس طرح ہم کرتے ہوئے معیار زندگی کی حقیقی وجوہات کی تعیین
اور نشان دہی کر سکیں.اگر چہ اس قسم کے اقتصادی تنزل کے اسباب کا تعین کسی
لمبے چوڑے حساب کتاب کے بغیر بھی بآسانی کیا جا سکتا ہے.سوشلزم میں چونکہ
196
Page 209
حکومت سرمایہ دار بن جاتی ہے اور اس پر کوئی مالی دباؤ یا پابندیاں نہیں ہوتیں اس
لئے وہ کسی احتساب کے خوف کے بغیر قومی سرمایہ استعمال کر سکتی ہے.اس کے پاس
جائزہ اور نگرانی کا کوئی ایسا انتظام بھی نہیں ہوتا جو اسے اس کی ناکامیوں، غلطیوں اور
معاشی ضیاع کے متعلق متنبہ کر سکے.اس صورت حال میں ہمیشہ بہت سے خطرات
منڈلاتے رہتے ہیں.اول یہ کہ ذاتی دلچپسی کا فقدان ہوتا ہے دوسرے یہ کہ سرمایہ
کاری سے حاصل ہونے والے نفع و نقصان سے آگاہ کرنے والا کوئی نظام موجود نہیں
ہوتا.اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سرمایہ کاری اور پیداوار کا باہمی تناسب بگڑ جاتا ہے اور
مالی ضیاع بڑھتا چلا جاتا ہے.نیز یہ کہ اشتراکی نظام میں سرمایہ کی تقسیم اور فراہمی کی
پالیسی پر کوئی نگرانی نہیں ہوتی.ایک سوشلسٹ حکومت کے پاس اپنی اقتصادی ترقی
کی حقیقی شرح کا باہر کی دنیا کی کھلی منڈی والی معیشت کی شرح ترقی سے موزانہ
کر کے جائزہ لینے کا کوئی پیمانہ نہیں ہوتا.سوشلسٹ معاشرہ کا ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ
اس میں دفاع، نگران اداروں اور قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں پر نسبتاً بہت
زیادہ اخراجات برداشت کرنے پڑتے ہیں.دوسرے اخراجات اگر یکساں بھی ہوں
تو بھی دفاع اور امن و امان قائم رکھنے کے لئے اخراجات کا تناسب دوسرے
معاشروں سے بہت زیادہ ہوتا ہے.یہ اور ایسے بعض دوسرے عوامل معیشت کے لئے
نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں.اس صورت حال میں یقینی اقتصادی تباہی کو مؤخر تو کیا
جا سکتا ہے لیکن اسے کلیہ اور ہمیشہ کے لئے ٹالا نہیں جا سکتا.اسلامی نظریه
اشتراکی نظام میں لوگ اقتصادی ترقی کے عمل میں براہ راست اور پوری تندہی
سے شرکت کی طرف مائل نہیں ہوتے لیکن اسلام میں سود کی ممانعت کے باوجود
197
Page 210
اقتصادی ترقی کے عمل میں شرکت کے لئے ترغیب موجود ہے.اسلام کے
نظام اقتصادیات میں سود کا لالچ نہ ہونے کے باعث جو سرمایہ پیدا وار کے عمل میں
شامل نہیں ہوتا اور بے کار پڑا رہتا ہے اسلام نے اس کا حل ایک ٹیکس کی صورت میں
پیش فرمایا ہے جسے زکوۃ کہا جاتا ہے.یہ وہ ٹیکس ہے جو کسی آمد یا منافع پر نہیں بلکہ
خود سرمایہ پر عائد کیا جاتا ہے.پس اس طرح اسلام سود سے بھی نجات دلاتا ہے اور
اشترا کی دنیا کے مخصوص مسائل سے بھی اس کا دامن پاک رہتا ہے.اسلام کے اقتصادی نظام اور سرمایہ دارانہ نظام میں بڑا واضح فرق ہے.مؤخر الذکر نظام سے وابستہ معاشروں میں سرمایہ چند ہاتھوں میں اکٹھا ہو جاتا ہے.اس کی وجہ سود کے ذریعہ سرمایہ کو بڑھانے کا لالچ ہے.بار بار سرمایہ کا روبار میں لگایا
جاتا ہے تا کہ شرح سود سے زیادہ منافع کمایا جائے.شرح سود سے بڑھ کر منافع
حاصل نہیں ہوگا تو لازماً نتیجہ معاشی زوال کی صورت میں نکلے گا.اسلام کے
اقتصادی نظام میں ایک شخص اس ڈر سے کہ کہیں زکوۃ کے باعث اس کا مال رفتہ رفتہ
ختم نہ ہو جائے لازماً اپنی فاضل رقم یا بچت کو کسی منافع بخش کاروبار میں لگائے گا تا کہ
زکوۃ دینے سے مال میں جو کمی واقع ہوئی ہے وہ پوری ہو سکے.اسلام کے نزدیک دنیا کے اقتصادی مسائل کا حل نہ تو سوشلزم میں ہے اور نہ
سرمایه دارانہ نظام میں.یہاں اس موضوع پر سیر حاصل بحث تو ممکن نہیں تاہم ہم
سرمایه دارانہ نظام کے نتیجہ میں پیدا ہونے والے اقتصادی عدم توازن پر ایک نظر
ڈالیں گے تاکہ مستقبل کے لئے کچھ سبق سیکھا جا سکے.سرمایہ دارانہ معاشرہ کی چار خصوصیات
قرآن کریم کی مندرجہ ذیل آیات میں بڑی صراحت کے ساتھ وہ علامات بیان
198
Page 211
ہوئی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ معاشرہ اقتصادی عدم توازن کا شکار ہو چکا ہے.كَلَّا بَلْ لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلا تَحْضُونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ وَتَأْكُلُونَ
التراث أكلاً لمَّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمَّاه ( سورة الفجر آیات ۱۸ تا ۲۱)
ترجمہ.خبردار! در حقیقت تم یتیم کی عزت نہیں کرتے.اور نہ ہی مسکین کو
کھانا کھلانے کی ایک دوسرے کو ترغیب دیتے ہو.اور تم ورثہ تمام تر
ہڑپ کر جاتے ہو.اور مال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو.مختصر طور پر یہ خصوصیات مندرجہ ذیل ہیں.1
(۱) یتامی کے ساتھ بے عزتی کا سلوک
(۲) غرباء کو کھانا کھلانے کی طرف عدم توجہ
(۳) دوسروں کی وراثت پر ناجائز قبضہ
(۴) چند ہاتھوں میں بے انتہا مال کا جمع ہونا
سرمایہ دارانہ نظام بالآ خر تباہی کی طرف لے جاتا ہے.اسلام سائینٹیفک سوشلزم
کے فلسفہ کی حمایت نہ کرتے ہوئے سرمایہ دارانہ نظام کے بعض پہلوؤں کو بھی مستردکر
دیتا ہے.قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے.ل
الْهَكُمُ التَّكَاثُرُه حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَه كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ
( سورۃ التکاثر آیات ۲ تا ۴)
ترجمہ: تمہیں غافل کر دیا ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی دوڑ نے.یہاں
تک کہ تم نے مقبروں کی بھی زیارت کی.خبردار! تم ضرور جان لو گے.دنیا کا بدلتا ہوا اقتصادی نظام
اگر چہ یہ کلیہ کہ سودی نظام کے ہاتھوں غریبوں کا استحصال بالآ خر سوشلسٹ بغاوت
199
Page 212
پر منتج ہوتا ہے بظاہر ایک قصہ پارینہ بن چکا ہے لیکن اگر گہری نظر سے دیکھا جائے تو
معلوم ہو گا کہ یہ محض ایک فریب نظر ہے.اس وقت ساری دنیا ہی امارت اور غربت
کی بنیاد پر تقسیم ہو چکی ہے.اس کا سہرا بڑی حد تک اس استحصال کے سر ہے جو
ترقی یافتہ سرمایہ دار ممالک نے پسماندہ ممالک کا کیا ہے.مشرقی یورپ کے سوشلسٹ
ممالک کا پشیمان ہو کر سرمایہ دارانہ نظام کی طرف لوٹنا ایک ایسا واقعہ ہے جس سے
استحصال کی یہ صورت حال اور بھی گھمبیر ہو گئی ہے.تیسری دنیا کی غریب اور مفلوک
الحال قوموں کا ابھی اور کتنا خون چوسا جائے گا، اس تصور سے ہی انسان کانپ کر رہ
جاتا ہے.بظاہر یہی نظر آتا ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام کے خونخوار بھیڑیوں کی پیاس ابھی
نہیں بجھی.سرمایہ دارانہ نظام اور سوشلزم نے دنیا کو دو بڑے اقتصادی فلسفے دیئے ہیں.یہ
بات واضح ہے کہ دونوں کے درمیان جاری محاذ آرائی کا دور اب ختم ہو چکا ہے.وہ
اقتصادی نظام جن کی بنیاد مارکس ازم اور لینن ازم پر تھی اب دنیا کے معاملات میں
کوئی خاص کردار ادا نہیں کر رہے.دوسری طرف مغرب کی نام نہاد آزاد معیشت
اپنی بظاہر فتح پر پھولی نہیں سما رہی.مشرقی بلاک کے جملہ ممالک اپنی نئی آزادی کے
حصول کے بعد اس جدو جہد میں مصروف ہیں کہ کسی طرح غربت کے ستائے ہوئے
اپنے لاکھوں کروڑوں عوام کی حالت زار کو بہتر بنا سکیں.ان مشرقی ممالک میں لے
دے کر صرف چین ہی ایک استثناء ہے.مشرق اور مغرب کے درمیان بعد اتنا نہیں ہے جتنا کہ شمال اور جنوب کے
ممالک کے مابین.شمال میں واقع پہلی دنیا کے ممالک افریقہ اور جنوبی امریکہ کے
تیسری دنیا کے ممالک سے صرف جغرافیائی طور پر ہی الگ نہیں بلکہ اقتصادی طور پر
بھی ان کے درمیان طویل فاصلے حائل ہیں.شمالی اور جنوبی امریکہ کے درمیان پایا
200
Page 213
جانے والا اقتصادی فرق یقیناً تکلیف دہ ہے لیکن اس سے کہیں زیادہ فرق یورپ اور
افریقہ کے مابین موجود ہے.افریقہ کی سرزمین جغرافیائی اعتبار سے یورپ کے
نزدیک ترین ہے مگر اقتصادی تفاوت کے لحاظ سے بعید ترین بھی ہے.ایک وقت تھا کہ سپر طاقتوں کے مابین پائی جانے والی رقابتوں کی وجہ سے دنیا
کے کمزور ممالک کو ایک طرح کا احساس تحفظ حاصل تھا لیکن اب صورت حال بدل چکی
ہے.سرد جنگ کے باعث غریب اقوام جو فوائد حاصل کر رہی تھیں برف پگھلنے کے
ساتھ ساتھ ان کے امکانات کم سے کم تر ہوتے چلے جائیں گے.تیسری دنیا کے
ممالک کی تجارتی منڈیوں پر قبضہ کرنے اور ان پر اپنی اجارہ داری قائم کرنے اور
انہیں ہمیشہ اپنے قابو میں رکھنے کے لئے امریکہ روس اور یورپ کے ممالک کے
درمیان پہلے سے کہیں بڑھ کر سخت مقابلہ ہونے والا ہے.مستقبل میں صرف جاپان ہی
امریکہ کا ایک اہم مد مقابل اور حریف نہیں ہو گا بلکہ یوروپین کمیونٹی European)
(Community کی تیز رفتار ترقی کے باعث ایک نیا یورپ بھی منصہ شہود پر آ رہا
ہے.مشرقی یورپ کی اس وسیع تر مشترکہ مارکیٹ میں امکانی شرکت سے امریکہ کے
لئے ان کا مقابلہ کرنا یورپ کے دوسرے حریف ممالک سے مقابلہ کی نسبت کہیں زیادہ
مشکل ہو گا.مشرقی یورپ اور روس کے کروڑوں لوگ اپنے معیار زندگی کو بلند کرنے کی
شدید ضرورت محسوس کر رہے ہیں اور بے تابی سے اس کے تبدیل ہونے کے منتظر
ہیں.ان کی محدود اندرونی مارکیٹ ان تمام ضروریات کو پورا کرنے کے لئے ناکافی
ہو گی اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اور بھی زیادہ ناکافی ہوتی چلی جائے گی.مشرقی یورپ اور روس میں بڑھتے ہوئے معیار زندگی کو سہارا دینے کے لئے بیرونی
منڈیوں کی سخت ضرورت ہوگی جس کو یوروپین کمیونٹی امریکہ اور جاپان پوری کر سکتے
201
Page 214
ہیں.اس صورت حال میں تیسری دنیا کے ممالک کے لئے درحقیقت امید کی کوئی
کرن نظر نہیں آتی.اور پھر افریقہ کے بدنصیب لوگوں کے لئے تو مایوسیوں کے
اندھیرے اور بھی گہرے ہو رہے ہیں.اقتصادی اور سیاسی اعتبار سے دنیا بھر کی ترقی یافتہ قوموں کے سیاست دان
مشرق بعید میں رونما ہونے والے سرمایہ دارانہ اقتصادی انقلاب کی طرف کچھ زیادہ
ہی متوجہ ہیں.مشرق بعید کے ان ممالک میں جاپان، جنوبی کوریا فارموسا
ہانگ کانگ اور سنگا پور شامل ہیں اور ایسا نظر آتا ہے جیسے مشرق بعید اور مغرب
ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہوں.لیکن جہاں تک انڈونیشیا، ملائشیا، کمبوڈیا، تھائی
لینڈ، برما، بنگلہ دیش، بھارت، سری لنکا اور پاکستان جیسے غریب اور ترقی پذیر ملکوں کا
سوال ہے ان کا تو مغربی ممالک سے فاصلہ اور بھی بڑھ گیا ہے.یوں لگتا ہے جیسے ان
ترقی پذیر ممالک کے سروں پر ایک پل تعمیر کیا جا رہا ہو جو مغرب اور مشرق بعید کے
ملکوں کے باہمی فاصلوں کو اور بھی کم کر دے گا.جاپان کے عظیم اقتصادی چیلنج کا مقابلہ کرنے اور اس کی تیز رفتار اقتصادی ترقی کو
روکنے کے لئے ایک طرف جہاں اندیشہ ہے کہ مشرق بعید کے دوسرے ممالک اب
امریکن سرمایہ یا ٹیکنالوجی وغیرہ سے مزید مستفید نہ ہو سکیں گے وہاں یہ بھی ممکن ہے
کہ امریکہ مشرق بعید کے اپنے ان اتحادیوں پر اپنا انحصار اور بھی بڑھا دے گا تاکہ
جاپان اور اقتصادی لحاظ سے عظیم تر متحدہ یورپ کے اقتصادی چیلنجوں کا مقابلہ کیا
جا سکے.یہ ساری صورت حال کرہ ارض پر بسنے والے انسان کے مستقبل کے لئے
کوئی اچھا شگون نہیں ہے.اس سے عالمی امن کی سب امیدوں پر پانی پھر سکتا ہے
اور اس بار امن کے یہ خواب سرمایہ دارانہ نظام اور کمیونزم کی باہمی نظریاتی کشمکش اور
رقابتوں کے باعث چکنا چور نہیں ہوں گے بلکہ اس کے عوامل کچھ اور ہوں گے.202
Page 215
مشرقی یورپ اور روس میں ہونے والی تبدیلیاں دنیا کے اقتصادی توازن پر کس
طرح اثر انداز ہوں گی، اس کے متعلق کوئی پیشگوئی کرنا قبل از وقت ہوگا.ابھی تو یہ
بھی نہیں کہا جا سکتا کہ ان ممالک کی سرمایہ دارانہ نظام کی طرف کبھی واپسی ہوگی بھی یا
نہیں علاوہ ازیں ان تبدیلیوں کی رفتار کا تعین بھی قبل از وقت ہو گا.مستقبل کے
امکانات جو بھی ہوں یہ بات یقینی ہے کہ یہ تبدیلیاں تیسری دنیا کے ممالک کی
اقتصادیات پر منفی اثرات مرتب کریں گی لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ یہ صورت
حال ہمیشہ ایسی نہیں رہے گی بلکہ سنگین سے سنگین تر ہوتی چلی جائے گی.اس حقیقت
سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ دنیا ایک عالمی تباہی کے راستہ پر چل نکلی ہے.اسلام سود کی کھوکھلی بنیادوں پر قائم سرمایہ دارانہ ممالک کو جو آج خوشی سے
پھولے نہیں سماتے متنبہ کرتا ہے کہ وہ بالآخر لازماً تباہ و برباد ہو جائیں گے.سرمایہ
دارانہ نظام کی سوشلزم پر حالیہ نام نہاد فتح انہیں ایک وقتی اور عارضی امن ہی دے سکتی
ہے.خود سرمایہ دارانہ نظام کے فلسفہ سے ایسی طاقتور بلائیں جنم لیں گی جو سوشلزم کو
اپنے مدمقابل نہ پا کر بڑھتے بڑھتے بے حد ہیبت ناک صورت اختیار کر لیں گی.سرمایہ دارانہ نظام کا آتش فشاں پہاڑ بالآ خر اتنی قوت سے پھٹے گا کہ ساری دنیا اس
کے زلزلہ سے تہ و بالا ہو کر رہ جائے گی.اسلام کا اقتصادی نظام
اسلام کے پیش کردہ سماجی نظام کی طرح اسلام کے اقتصادی نظام کی ابتداء بھی
اسی بنیادی حقیقت سے ہوتی ہے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا
پیدا کردہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو جو بہت سی نعمتیں عطا فرمائی ہیں وہ
بطور امانت کے ہیں.انسان بحیثیت امین اس امر کا جوابدہ ہے کہ کیا اس نے امانت
203
Page 216
کا حق ادا کیا ہے؟ ایک شخص کا دولت مند ہونا یا دولت سے محروم ہونا یہ دونوں حالتیں
دراصل اس کی آزمائش کی مختلف شکلیں ہیں تا کہ یہ معلوم ہو سکے کہ کون خوشحالی اور
تنگ دستی میں اپنے محاسبہ کا فکر رکھتا ہے اور کون ہے جو بنی نوع انسان کی تکالیف کے
احساس سے عاری ہو جاتا ہے اور اسے خیال تک نہیں آتا کہ انسانیت کن مصائب
سے دو چار ہے.قرآن کریم بار بار ہمیں یاد دلاتا ہے کہ
280
وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
(سورۃ آل عمران آیت ۱۹۰)
ترجمہ:.اور اللہ ہی کے لئے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت.اور
اللہ ہر چیز پر جسے وہ چاہے دائگی قدرت رکھتا ہے.پھر قرآن کریم ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے سب کچھ مخلوق کے
لئے پیدا کیا ہے تو چاہئے کہ اس میں دوسروں کے حصہ کو بھی تسلیم کیا جائے.6260
أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذَا لَّا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا.(سورۃ النساء آیت ۵۴)
ترجمہ:.کیا ان کا بادشاہت میں سے کوئی حصہ ہے.تب تو وہ لوگوں کو
( ہرگز اس میں سے ) کھجور کی گٹھلی کی لکیر کے برابر بھی نہیں دیں گے.وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِيْنَ فُضِّلُوا بِرَادِي
عَلَى مَامَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ ، أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُوْنَ
( سورۃ النحل آیت ۷۲ )
ترجمہ.اور اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض دوسروں پر رزق میں فضیلت
بخشی ہے.پس وہ لوگ جنہیں فضیلت دی گئی وہ کبھی اپنے رزق کو ان کی
طرف جو ان کے ماتحت ہیں اس طرح لوٹانے والے نہیں کہ وہ اس میں
ان کے برابر ہو جائیں.پھر کیا وہ اللہ کی نعمت کے بارہ میں جھگڑتے ہیں؟
204
Page 217
انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ حق امانت پوری ایمانداری اور انصاف سے ادا
کرے.چنانچہ قرآن کریم فرماتا ہے:
ه و و وه - ورد
11-0
إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْآمَنتِ إِلَى أَهْلِهَا وَ إِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ
تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ دَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا
ط
(سورۃ النساء آیت ۵۹)
ترجمہ :.یقینا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے حق داروں کے
سپرد کیا کرو اور جب تم لوگوں کے درمیان حکومت کرو تو انصاف کے
ساتھ حکومت کرو.یقیناً بہت ہی عمدہ ہے جو اللہ تمہیں نصیحت کرتا
ہے.یقیناً اللہ بہت سننے والا (اور ) گہری نظر رکھنے والا ہے.یہ حقیقت کہ مادی دولت آزمائش کا ایک ذریعہ ہے.قرآن کریم ان الفاظ میں
بیان کرتا ہے.280
- No.To en
إِنَّمَا أَمْوَالَكُمْ وَ أَوْلادَكُمْ فِتْنَةٌ وَاللهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ (سورة التغابن آیت ١٦ )
ترجمہ :.تمہارے اموال اور تمہاری اولا د محض آزمائش ہیں.اور وہ اللہ
ہی ہے جس کے پاس بہت بڑا اجر ہے.اسلام میں ملکیت کے ضمن میں ایک اہم بات یہ ہے کہ بعض پیداواری ذرائع کو
فرد کی ذاتی ملکیت قرار دینے کی بجائے مجموعی طور پر بنی نوع انسان کی ملکیت قرار دیا
گیا ہے.چنانچہ اسلامی تعلیم کے مطابق معدنی ذرائع اور سمندری پیداوار کسی فرد
واحد یا چند افراد کی ملکیت نہیں ہوسکتی.زكوة
زکوۃ اسلام کے پانچ بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے.باقی ارکان کلمہ
205
Page 218
لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ الله ، نماز ماہ رمضان کے روزے رکھنا اور مکہ
معظمہ میں بیت اللہ کا حج کرنا ہیں.قرآن کریم فرماتا ہے.ا وہ وہ وہ.وہ
واقيموا الصلوة واتوا الزكوة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون
(سورۃ النور آیت ۵۷)
ترجمہ:.اور نماز کو قائم کرو اور زکوۃ ادا کرو اور رسول کی اطاعت کرو
تا کہ تم پر رحم کیا جائے.عربی لفظ زکوۃ کے لفظی معنی کسی چیز کو پاک کرنے کے ہیں.اس لحاظ سے دولت
پر لازمی ٹیکس یعنی زکوۃ کی ادائیگی کے معنی یہ ہوں گے کہ باقی ماندہ مال مومنوں کے
لئے پاک اور جائز ہو گیا ہے.زکوۃ کی شرح زیر استعمال اثاثوں پر اڑھائی فیصد
ہے جب کہ یہ اثاثے ایک مقررہ حد سے زیادہ ہوں اور ایک ہی شخص کی ملکیت میں
ان پر ایک سال سے زائد عرصہ گزر جائے.اس ٹیکس کی شرح پر اگرچہ بہت کچھ کہا جا چکا ہے لیکن قرآن کریم میں کسی معین
شرح کا حوالہ نہیں ملتا.میں اس سلسلہ میں قرون وسطی کے علماء کے کٹر نظریہ سے
اختلاف کرتا ہوں اور یقین رکھتا ہوں کہ زکوۃ کی شرح میں لچک رکھی گئی ہے اس لئے
اس کا تعین ہر ملک کے اقتصادی حالات کے مطابق کیا جانا چاہئے.زکوۃ ایک خاص
حد سے زیادہ مال پر عائد ہونے والا ٹیکس ہے اور صرف بعض قسم کے اخراجات کے
لئے استعمال ہو سکتا ہے.زکوۃ کے یہ مصارف قرآن کریم کی مندرجہ ذیل آیت میں
بیان ہوئے ہیں.إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِيْن والعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَرِمِينَ وَ فِي سَبِيْلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللَّهُ
عليمٌ حَكِيمٌ
206
(سورۃ التوبہ آیت (۶۰)
Page 219
ترجمہ :.صدقات تو محض محتاجوں اور مسکینوں اور ان (صدقات) کا
انتظام کرنے والوں اور جن کی تالیف قلب کی جارہی ہو اور گردنوں کو
آزاد کرانے اور چٹی میں مبتلا لوگوں اور اللہ کی راہ میں عمومی خرچ کرنے
اور مسافروں کے لئے ہیں.یہ اللہ کی طرف سے ایک فرض ہے.اور
اللہ دائمی علم والا (اور ) بہت حکمت والا ہے.ย
اس حکم کو نافذ کرنے کا انتظام بیت المال کے سپرد ہے.خلافت راشدہ میں پہلے دو
خلفاء یعنی حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق صدقات کو جلد از جلد مستحقین
میں تقسیم کرنے میں بڑی شہرت رکھتے ہیں.آپ دونوں ذاتی دلچسپی لے کر زکوۃ کی
فوری تقسیم کو یقینی بناتے تھے.یہ وہ مملکت تھی جو پہلی فلاحی ریاست کے نام سے موسوم
ہوئی.صدقات کی تقسیم کا یہ نظام عباسی دور میں صدیوں تک بڑی کامیابی سے چلتا رہا.جیسا کہ پہلے واضح کیا جا چکا ہے اسلام کے اقتصادی نظام کو چلانے والی قوت
سود نہیں بلکہ زکوۃ ہے.جب ہم اس نظام کو عملی شکل میں دیکھتے ہیں تو اس میں اور
دیگر اقتصادی نظاموں میں بہت سے اور فرق بھی نظر آنے لگتے ہیں اور ایک بالکل
مختلف اقتصادی نقشہ ابھرتا ہے.سرمایہ پر جس شرح سے ٹیکس ادا کیا جاتا ہے اس سے زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ
سرمایہ میں اضافہ ہونا ضروری ہے ورنہ بے کار پڑا ہوا سرمایہ خواہ زیادہ ہو یا کم لمبے
عرصہ تک نہیں رہ سکتا.بعینہ اسی اصول پر زکوۃ ایک حقیقی اسلامی ریاست کی معیشت
کو ترقی دیتی.ہے
ایک ایسے شخص کا تصور کریں جس کے پاس تھوڑا سرمایہ ہے.وہ نہ تو اس قابل
ہے کہ براہ راست تجارت میں حصہ لے سکے اور نہ بینک موجود ہیں جو اس کی رقم پر
سود ادا کر سکیں.اگر وہ صاحب نصاب ہے یعنی اس کا سرمایہ اتنا ہے کہ اس پر زکوۃ
207
Page 220
عائد ہوتی ہے تو زکوۃ لینے والے ہر سال اس کے دروازہ پر دستک دیں گے.ایسے
افراد کے پاس دو ہی راستے ہیں یا تو وہ خود اپنے مال کو کسی منافع بخش کام میں
لگا دیں یا پھر سب مل کر کوئی چھوٹا بڑا کاروبار شروع کریں.اس طرح نفع و نقصان
میں شراکت کی بنیاد پر مشترکہ کاروبار شروع ہو جائیں گے.چھوٹی چھوٹی تجارتی
کمپنیاں وجود میں آئیں گی یا بڑی کمپنیوں میں پبلک حصص رکھے جائیں گے.ان
کمپنیوں پر کسی مالی ادارہ کا کوئی ایسا قرض نہیں ہو گا جسے انہوں نے سود کے ساتھ
واپس لوٹانا ہو.ایسی کمپنیوں کا سرمایہ دارانہ نظام کے تحت قائم شدہ کمپنیوں
موازنہ کیا جائے تو معلوم ہو گا کہ اول الذکر کمپنیوں کو اقتصادی بحرانوں اور دیگر
مشکل حالات میں ایک بالکل مختلف صورت حال کا سامنا ہو گا.سرمایہ دارانہ
اقتصادی نظام میں اگر تجارتی یا صنعتی پیداوار مانگ کم ہونے کی وجہ سے ماند پڑ جائے
تو نوبت دیوالیہ پن تک پہنچ سکتی ہے.جو سود انہیں اپنے قرضوں پر ادا کرنا پڑتا ہے
وہ مسلسل بڑھتا ہی چلا جاتا ہے یہاں تک کہ ایسی کمپنیوں کا قائم رکھنا ہی ناممکن ہو جاتا
ہے.لیکن اگر دوسری طرف کوئی اقتصادی نظام اسلامی اصول کے مطابق چل رہا ہے
تو کاروبار میں مندے کی وجہ سے صنعت و تجارت تباہ نہیں ہو گی بلکہ عارضی طور پر
اس پر سرمائی نیند کی سی کیفیت طاری ہو جائے گی.نظام قدرت میں بھی ہم دیکھتے
ہیں کہ انتہائی مشکلات اور تنگی کے زمانہ میں بہترین چیز کو اسی طریق پر بچایا جاتا ہے.جب توانائی کم ہو جائے تو کام کا بوجھ بھی کم پڑتا ہے تا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ زندہ رہنے
کے لئے کم سے کم توانائی بھی نہ مل سکے.چنانچہ اسلام کے مالی نظام میں سود کی
ادائیگی کا مسلسل بڑھنے والا دباؤ نہیں ہوتا اس لئے اس میں کاروباری مندے کو
برداشت کرنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے اور یہ بُرے وقت میں بھی بڑے سے
بڑے چیلنجوں کا سامنا کرسکتا ہے.208
Page 221
سود کی ممانعت
اسلام کے اقتصادی نظام میں سود کا قطعاً کوئی عمل دخل نہیں ہے.کوئی تاریخی یا
حالیہ شہادت نہیں ملتی کہ سود کے نہ ہونے کی نتیجہ میں افراط زر کی مصیبت خوفناک حد
تک بڑھ گئی ہو اور قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی ہوں.سود کا ہونا یا نہ ہونا
افراط زر پر کس طرح اثر انداز ہوتا ہے اس کے موازنہ کا ایک دلچسپ موقع موجودہ
زمانہ میں پیدا ہوا.ماؤزے تنگ کی قیادت میں چین کی حکومت نے بہت سے
اقتصادی تجربات کئے ان میں سے بعض تو کامیاب نہ ہو سکے مگر بعض کے بہت
شاندار نتائج نکلے.ماؤزے تنگ کے سارے دور میں افراط زر میں کوئی قابل ذکر
اضافہ نہیں ہوا بلکہ حقیقت یہ ہے کہ بالآخر مجموعی پیداوار میں اضافہ کا رجحان پیدا ہوا
اور قیمتیں گرنی شروع ہو گئیں.چین کے برعکس اسرائیل میں (جو شاید دنیا بھر میں
سرمایہ دارانہ نظام کا سب سے بڑا نمائندہ ملک ہے ) افراطِ زر کی شرح دنیا میں سب
سے زیادہ ریکارڈ کی گئی ہے.البتہ لاطینی امریکہ کے ممالک یقیناً ایک استثناء ہیں اسی
طرح یورپ خصوصاً جرمنی میں دوسری جنگ عظیم کے فوراً بعد افراط زر میں بے تحاشا
اضافہ ضرور ایک غیر معمولی واقعہ تھا.لیکن جنگ کے بعد سارے یورپ کو ایک
غیر معمولی صورت حال کا سامنا تھا اور یہ اضافہ بھی اسی کا نتیجہ تھا.پس عام حالات
میں کسی بھی معیشت میں سود کے کردار کے متعلق وثوق سے کہا جا سکتا ہے کہ افراط زر
اور سود دونوں لازم و ملزوم ہیں.برطانیہ میں شرح سود کا مسئلہ
برطانیہ میں بلند شرح سود کے مفید پہلوؤں پر حالیہ گرما گرم بحث اس
موضوع پر مطالعہ کے لئے ایک دلچسپ مثال ہے.ٹوری یعنی قدامت پسند حکومت
209
Page 222
نے ایک لمبے عرصہ تک سود کی شرح کو خطرناک حد تک بلند کئے رکھا.ان کے بقول
اس کا واحد مقصد نجی سطح پر دولت کے اسراف کو روکنا تھا تا کہ افراط زر پر قابو پایا
جاسکے.حکومت کی اس پالیسی سے جو مشکلات پیدا ہوئی ہیں ان کی وجہ سے معیشت
سخت بدحالی کا شکار ہو چکی ہے.اس صورت حال کے مطالعہ سے کئی سبق سیکھے جا سکتے
ہیں.علاوہ دیگر باتوں کے یہ بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ کس طرح بعض اہم
اقتصادی فیصلے ایک ایسے نظریہ کی بنیاد پر کر لئے جاتے ہیں جو خود ابھی پایہ ثبوت تک
نہیں پہنچا.حکومت نے شرح سود کو اتنے طویل عرصہ سے جو مصنوعی طور پر بڑھا رکھا
ہے اس کی یہی توجیہ کی جاسکتی ہے کہ حکومت کا خیال ہے کہ شرح سود جس قدر بڑھے
گی افراط زر میں اسی قدر کمی ہوگی.برطانیہ کے موجودہ حالات میں افراط زر کی
بڑھتی ہوئی شرح کے متعلق ہمارا مطالعہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس کی ذمہ داری صرف سود
پر نہیں ڈالی جا سکتی بلکہ اس کی اور بھی کئی وجوہات ہوسکتی ہیں.مثلاً معاشی نظام میں
بدانتظامی یا مجموعی طور پر ناقص پالیسی.سود کی شرح بڑھانے سے تو صرف یہ ہوا ہے
کہ توجہ اصل وجوہات کی طرف سے ہٹ گئی ہے اور مورد الزام کسی اور کو ٹھہرا دیا گیا
ہے.اس حکمت عملی سے ممکن ہے کہ شروع شروع میں افراط زر کا مقابلہ کرتے وقت
یوں لگے جیسے کامیابی ہو رہی ہے مگر بالآخر اس پالیسی کے ثانوی اثرات بھی مرتب
ہوں گے.بلکہ امر واقعہ یہ ہے کہ ابھی سے ایسے طاقت ور عوامل کارفرما ہو چکے ہیں
جو ان اثرات کو جنم دیں گے.ملک میں ایک ایسا معاشی زوال پیدا ہو گا جسے سنبھالنا
بہت مشکل ہوگا اور بے روزگاری میں اضافہ ہو جائے گا.یہ کیسے مان لیا جائے کہ
کنزرویٹو حکومت کو بڑے بڑے ماہرین اقتصادیات، تجربه کار مالی منصوبہ بندی
کرنے والوں، بینکوں اور دانش وروں کے مشورے اور رہنمائی حاصل نہیں ہے.سود
کی اس بلند شرح کو کم کرنے میں عمداً جو تاخیر کی جا رہی ہے اس کی کوئی نہ کوئی وجہ
210
Page 223
ضرور ہے.حکومت سے کہا جا رہا ہے کہ قومی معیشت کی بقا کے لئے افراطِ زر کے
رجحان کو بلند شرح سود کے ذریعہ کم کرنا بے حد ضروری ہے.دراصل یہ محض
بہانہ سازی ہے.کہیں ایسا تو نہیں کہ اگر شرح سود میں اس وقت کمی کی گئی تو موجودہ
حکومت کے مفاد کو نقصان پہنچے گا ؟ لگتا ہے کہ شرح سود میں کمی فی الحال معرض التوا
میں ڈال کر آئندہ انتخابات سے ذرا پہلے اس کا اعلان کر دیا جائے گا اور اس طرح
لوگوں کو جو سکھ کا سانس آئے گا یقیناً اس سے کنزرویٹو حکومت کو سیاسی مفاد حاصل ہو
گا.لیکن اگر یہی کمی قبل از وقت کر دی گئی تو اندیشہ ہے کہ وہ ثانوی اثرات ظاہر ہونا
شروع ہو جائیں گے جن کی طرف پہلے اشارہ کیا جا چکا ہے.اس صورت میں شرح
سود میں تخفیف سے حاصل ہونے والا وقتی سکون سیاسی مفاد کو برباد کرنے کا باعث
بن سکتا ہے.بعض عوامل جن کے باعث یہ نقصان دہ صورت حال پیدا ہو چکی ہے درج ذیل
ہیں:
(۱) بلند شرح سود نے نہ صرف عام لوگوں کی قوت خرید کو بے حد کمزور کر دیا ہے
بلکہ صنعت و حرفت کا گلا گھونٹ کر رکھ دیا ہے.(ب) بلند شرح سود نے بنیادی ضروریات زندگی کے حصول کے لئے برطانوی
لوگوں کی بڑی تعداد کو بری طرح متاثر کیا ہے.سر چھپانے کے لئے چھت تعمیر کرنی
ہو تو لوگ خوب سوچ سمجھ کر قرض لیتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ قرض کی اقساط ادا
کرنے کے لئے انہیں اپنی روز مرہ کی ضروریات کو قربان کرنا پڑے گا.یہ لوگ تو
غیر ضروری اور فضول اخراجات کے پہلے ہی متحمل نہیں تھے.برطانوی معاشرہ کا یہ
طبقہ یقیناً افراط زر کے رجحان کا ذمہ دار قرار نہیں دیا جاسکتا.بدقسمتی سے یہ وہ لوگ
ہیں جنہیں افراط زرکو روکنے کے لئے کئے جانے والے نام نہاد اقدامات کی سخت سزا
211
Page 224
بھگتنا پڑی ہے.یادر ہے کہ ان اقدامات کا مقصد یہ بتایا گیا تھا کہ ان سے قیمتوں
میں کمی ہوگی اور عام آدمی کو فائدہ پہنچے گا.مگر ہوا یہ کہ قرض لے کر جو مکان تعمیر کئے
گئے تھے ان کی قیمتیں تیزی سے گرنا شروع ہو گئیں.اب لوگوں کی حالت یہ ہے کہ نہ
جائے رفتن نہ پائے ماندن نہ تو وہ قرض کی بڑی بڑی قسطیں ادا کر سکتے ہیں اور نہ ہی
انہیں اس جائیداد کا کوئی مناسب خریدار مل رہا ہے..(ج) افراط زر کا معاملہ خاصا پیچیدہ ہے.اگر چہ میرے خطاب کا یہ مقصد تو نہیں
کہ اس موضوع پر کوئی طویل اور غیر ضروری بحث میں الجھا جائے تاہم بعض وجوہات
کے باعث جن کا ذکر بعد میں ہو گا آپ کی اجازت سے اس موضوع پر کچھ کہنا
چاہوں گا.افراط زر کی دیگر وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ خریدار کی جیب میں
وافر رقم سے طلب تو مصنوعی طور پر بڑھ جاتی ہے مگر رسد میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا.لوگوں کے پاس پیسہ تو ہوتا ہے مگر مارکیٹ میں اشیائے خرید کی رسد میں کمی آجاتی
ہے.قوت خرید تو بڑھ جاتی ہے مگر خریدی جا سکنے والی چیزوں کی فراہمی گھٹ جاتی
ہے.لیکن برطانیہ کی معیشت میں غالباً یہ صورت حال نہیں ہے.یہاں زیر گردش
سرمایہ کے زیادہ ہونے سے ملکی مارکیٹ میں صنعتی پیداوار کی کھپت میں اضافہ ہوا ہے
اور یہ امر بڑی حد تک برطانوی صنعت کے لئے باعث تقویت ہے.اس سلسلہ میں
ٹیکسوں میں کمی اور عالمی منڈی میں پاؤنڈ سٹرلنگ کی مناسب شرح تبادلہ نے بھی
مثبت کردار ادا کیا ہے.برطانوی پاؤنڈ کی اس معتدل شرح تبادلہ کی وجہ سے
برطانوی مصنوعات کے غیر ملکی خریدار پیدا ہوئے ہیں جس کا فائدہ برطانوی صنعت کو
ہوا ہے جسے پہلے ہی اپنی پیداوار کی مقامی طور پر بڑھتی ہوئی مانگ اور کھپت سے مدد
مل رہی تھی.212
Page 225
اس صورت میں منطقی نتیجہ تو یہ نکلنا چاہئے تھا کہ مصنوعات کی قیمتوں میں کمی
ہو جاتی.ظاہر ہے کہ پیداوار میں اضافہ سے جو منافع حاصل ہوتا ہے اسی میں سے
مصنوعات کی تیاری پر اٹھنے والے عمومی اخراجات مثلاً عمارت کے کرائے، بجلی کے
بل وغیرہ بسہولت ادا ہو جانے چاہئیں اور اصل لاگت بے حد کم ہو جانی چاہئے.صنعت کار زیادہ منافع کمانا چاہتا ہے تو بھی اس کے پاس قیمتوں میں کمی کرنے کی
کافی گنجائش موجود تھی لیکن برطانوی معیشت اپنے طبعی استحکام اور ترقی کی بجائے
الٹا زوال کا شکار ہے جس کی وجہ طویل عرصہ سے نافذ بلند شرح سود ہے.اندیشہ
ہے کہ مستقبل میں اس کے اور بھی زیادہ خطرناک نتائج برآمد ہوں گے.اس کے
ساتھ ساتھ جو غیر ملکی منڈیاں ایک ایک کر کے ان کے ہاتھ سے نکل جائیں گی ان کا
از سر نو حصول بھی مشکل ہو جائے گا.یورپ میں تبدیلیوں کی وجہ سے وہاں کی معاشی
طاقت کا مرکز ثقل مغربی جرمنی (جسے اب جرمنی کہنا چاہئے ) منتقل ہو رہا ہے.اس
کے نتیجہ میں اس کی معیشت مضبوط تر ہو رہی ہے.ظاہر ہے کہ برطانوی معیشت کے
لئے یہ کوئی خوش آئند امر نہیں ہے.اس کے علاوہ برطانوی معیشت پر بلند شرح سود
کے کچھ ثانوی اثرات بھی پڑے ہیں جو بالکل منفی ہیں اور جن کی طرف پہلے اشارہ
کیا جاچکا ہے.سود کی شرح میں کمی کا اعلان اب ضروری ہو چکا ہے.موجودہ
حکومت اس اعلان کا وقت آگے پیچھے کرنے کی ناکام کوشش تو کر سکتی ہے لیکن
آئندہ اگر کنزرویٹو حکومت ہی آئی تو اسے اپنی ہی پارٹی کی سابقہ حکومت کی طرف
سے سنگین مسائل ورثہ میں ملیں گے.اس بحث کا لب لباب اور دنیا بھر کے
پالیسی سازوں کے لئے لمحہ فکر یہ یہ ہے کہ قومی معیشت کو کنٹرول کرنے کے لئے سود
کو آلہ کار بنانا فری مارکیٹ اکانومی کے نظریہ کی جڑوں پر تبر رکھنے کے مترادف
ہے.سودی سرمایہ کے فلسفہ پر قائم نظام معیشت کو درحقیقت آزاد نہیں کہا جا سکتا
213
Page 226
جس میں حکومت کو شرح سود کو بڑھانے یا گھٹانے کے مکمل اختیارات حاصل ہوں.اسلام کے اقتصادی نظام میں ایسے اقدامات کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے جنہیں
حکومت استحصال کا ذریعہ بنا سکے.سود کے دیگر نقصانات
سود کے بعض دیگر پہلوؤں کا ذکر یہاں بے محل نہیں ہو گا.بینک باہمی لین دین میں
جس شرح سے سود ادا کرتے ہیں وہ بڑے پیمانہ پر جمع کروائے گئے سرمایہ پر ہی
لاگو ہوتی ہے.عام سیونگ اکاؤنٹس پر اس شرح سود سے سود ادا نہیں کیا جاتا.باوجود اس کے کہ اصل زر اور سود سے حاصل ہونے والی رقوم پر سود ملتا ہے پھر بھی
چھوٹے اکاؤنٹس پر ملنے والا سود پیسے کی حقیقی قوت خرید سے بہت کم ہوتا ہے.اگر چہ
سود کی قلیل المیعاد شرح کم و بیش ہوتی رہتی ہے مگر دیکھا جائے تو انجام کار چھوٹے
ڈیپازٹ کے ذریعہ کمایا جانے والا سود افراط زر کی شرح سے کم ہوتا ہے.دوسری
طرف اگر اتنا ہی سرمایہ کا روبار میں لگایا جائے تو اس میں سرمایہ بڑھنے کی درحقیقت
بڑی گنجائش ہوتی ہے.سودی معاشرہ میں سرمایہ دار قرض دینے کے لئے ہمیشہ تیار رہتا ہے.قطع نظر
اس کے کہ قرض لینے والا رقم لوٹا بھی سکے گا یا نہیں.جہاں تک قرض لینے والوں کا
تعلق ہے ان میں سے معدودے چند ہی ہیں جو سنجیدگی سے غور کرتے ہیں کہ ان میں
قرض کو لوٹانے کی طاقت ہے یا نہیں.وہ نہیں جانتے کہ شائی لاک (Shylock)
جیسے ظالم ساہوکاروں اور بڑے بڑے مالی اداروں اور بینکوں سے قرض لینا دراصل
مستقبل کی اپنی ہی آمدنی میں سے قرض لینے کے مترادف ہے.سودی قرض کے یوں
214
Page 227
بآسانی مل جانے سے اپنی چادر دیکھے بغیر پاؤں پھیلانے کی عادت اور زیادہ بڑھتی
چلی جاتی ہے.لوگ زیادہ خرچ کرنے لگ جاتے ہیں اور ان کی قرض لوٹانے کی
طاقت کم ہوتی جاتی ہے.ایسے معاشرہ میں صارفین کی مانگ کو پورا کرنے کے لئے
پیداوار میں اضافہ تو ہو جاتا ہے لیکن یہ ایک غیر حقیقی اضافہ ہوتا ہے.ایک ایسا
معاشرہ جہاں معیار زندگی کو بلند سے بلند تر کرنے کی دوڑ ایک جنون کی شکل اختیار کر
چکی ہو وہاں اشیائے صرف کے نت نئے ماڈلوں کی تشہیر سے یہ جنون بڑھتا ہی چلا
جاتا ہے.ان اشتہارات کے ذریعہ عوام امراء کے پرتعیش طرز زندگی سے متعارف
ہوتے ہیں.نئے سے نئے ڈیزائن کے فرنیچر کو دیکھ کر ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ
جاتی ہیں.تفریحی مقامات پر بنے ہوئے چھوٹے چھوٹے پر تعیش گھر اور ان میں طرح
طرح کے برقی مشینی آلات سے آراستہ جدید طرز کے باورچی خانے اور غسل خانے
ان کی توجہ کا مرکز بن جاتے ہیں.یہاں تک کہ کم استطاعت رکھنے والے لوگ اپنی
خواہشات کی تکمیل کے لئے نہ چاہتے ہوئے بھی اس جھوٹی چکا چوند کا پیچھا کرنے لگ
جاتے ہیں جو سود پر انہیں بآسانی مل جاتی ہے.نتیجہ صاف ظاہر ہے کہ خرچ آمد سے
بڑھ جاتا ہے.اگر وہ اپنا قرض بلا سود بھی واپس کریں تو پھر بھی قرض اگر چہ موجودہ
قوت خرید کو تو بظاہر بڑھاتا ہے لیکن دراصل مستقبل کی قوت خرید کا گلا گھونٹ کر رکھ
دیتا ہے.مثلاً ایک شخص ایک ہزار ڈالر ماہوار کماتا ہے اور فرض کریں کہ وہ چالیس
ہزار ڈالر قرض لے کر مہنگی اشیاء خریدتا ہے.اب اس شخص کی قرض واپس کرنے کی
قوت کا تعین اس کی ماہانہ بچت سے ہی ہو گا.فرض کریں کہ وہ اپنا پیٹ کاٹ کر بمشکل
چھ سو ڈالر ماہوار میں گزارہ کرنے کی کوشش کرتا ہے.اس صورت میں اس کی ماہوار
بچت چار سو ڈالر ہو گی.اس تنگ بجٹ میں اسے آئندہ ایک سو ماہ گزارہ کرنا ہوگا
تا کہ وہ اس قرض کو اتار سکے جو چالیس ہزار ڈالر کے شاہانہ خرچ کی وجہ سے اسے
215
Page 228
اٹھانا پڑا تھا حالانکہ ابھی یہ قرض سود کے بغیر تھا.ہوا یہ ہے کہ اس نے اپنے مستقبل
کے ایک سو ماہ یعنی آٹھ سال چار ماہ سے یہ رقم ادھار لی ہے تا کہ اسے اس سارے
عرصہ کے آغاز میں ہی خرچ کیا جا سکے.اس کا فائدہ اسے صرف یہ ہوا کہ آٹھ سال
تک انتظار کرنے کی بجائے اس کی خواہش کی فوری تکمیل ہو گئی اور اس کی بے صبری
کو قرار آ گیا.لیکن اگر اسے چالیس ہزار کے قرض پر سود بھی ادا کرنا پڑتا ہے تو پھر وہ
اس سے کہیں زیادہ بدتر حالت کا شکار ہو جائے گا.مثال کے طور پر اگر شرح سود
چودہ فیصد ہے تو اس کا کل قرض جو اس نے واپس کرنا ہے اس اصل رقم سے کہیں
زیادہ بنتا ہے جو اس نے قرض لی تھی.پس اس کی قرض واپس کرنے کی طاقت مزید
کم ہو جائے گی اور عرصہ ادا ئیگی بہت طویل ہو جائے گا.ایسے شخص کو قریباً بیس سال
تک صبر کے ساتھ اپنی بے صبری کی سزا بھگتنی پڑے گی.اسے ماہانہ پانچ سو ڈالر کے
حساب سے قرض واپس کرنا پڑے گا اور سود در سود کی وجہ سے تقریباً ایک لاکھ ہیں
ہزار ڈالر کی ادائیگی کرنی ہوگی.اب دیکھئے نقصان یقینی طور پر قرض خواہ کو نہیں بلکہ
قرض دار کو اٹھانا پڑے گا.قرض خواہ تو ایک بہت بڑے طاقتور استحصالی نظام کا حصہ
ہے جو افراط زر اور قرض کے ضائع ہو جانے کے امکانات کا جائزہ لینے کے بعد ہی
اس ضمانت پر قرض دیتا ہے کہ آخر کار اس کی تجوری اور زیادہ بھر جائے گی.مگر
افراطِ زر کے نتیجہ میں قرض لینے والوں کی حالت پہلے سے بھی بدتر ہو جائے گی اور
اس کی قوت خرید میں مسلسل کمی ہوتی چلی جائے گی.اگر پہلے چھ سو ڈالر ماہوار میں
بمشکل گزارہ ہوتا تھا تو اب اتنی رقم میں گزارہ کرنا بالکل ناممکن ہو جائے گا.اور اتنے
خوش قسمت تو کم لوگ ہی ہوں گے جن کی سالانہ آمد میں اسی قدر اضافہ بھی ہو جائے
جس قدر افراط زر کی شرح میں اضافہ ہوا ہے.ایک ایسے معاشرہ میں جہاں لوگ مادی لذات کے حد سے زیادہ متلاشی ہو چکے ہوں
216
Page 229
وہاں صورت حال اور بھی بگڑ جاتی ہے.چند لمحوں کی شاہ خرچی اور داد عیش کے بعد
تنگ دستی کا ایک طویل اور بے کیف زمانہ کاٹنا پڑتا ہے.حالانکہ یہ ان کا اپنا فیصلہ تھا
اور وہ سمجھتے تھے کہ کسی نہ کسی طرح تنگی ترشی میں گزارہ کر لیں گے.نتیجہ پہلے
سے بھی زیادہ لا پرواہی سے اور نتائج و عواقب کی پرواہ کئے بغیر مزید قرض لے لیا
جاتا ہے اور اس طرح خرچ آمد سے کہیں زیادہ بڑھ جاتا ہے.درحقیقت آنے
والے سالہا سال کی کمائی قرض دینے والے بینکوں اور اسی قسم کے دوسرے مالی
اداروں کے پاس رہن رکھ دی جاتی ہے.سودی اقساط کی ادائیگی کا بوجھ بڑھتا چلا
جاتا ہے اور اس سے پیدا ہونے والے مسائل مقروض کو اپنی گرفت میں لے لیتے
ہیں.ان حالات میں معیشت بڑی سرعت کے ساتھ خوفناک بحران کی طرف بڑھنے
لگتی ہے.آخر آپ کب تک اپنے مستقبل کو حال کے پاس رہن رکھ سکتے ہیں.غیر
ذمہ دارانہ اور بے دریغ قسم کی فضول خرچیاں ایک دن لازما رنگ لائیں گی اور آپ
ایک زبر دست مالی بحران میں مبتلا ہو جائیں گے.افراط زر میں بے پناہ اضافہ
ہو جائے گا.افراط زر کا مقابلہ کرنے کے لئے سود کی شرح میں اضافہ ہوگا اور لوگوں
کے پاس خرچ کرنے کو پیسے کم رہ جائیں گے جس کا نتیجہ معاشی تباہی کے سوا کچھ ہو ہی
نہیں سکتا.اگر یہ صورت حال ایک ملک تک محدود رہے تو بھی قابل قبول نہیں ہونی
چاہئے لیکن جب انہی وجوہات کی بنا پر دنیا بھر کے ممالک معاشی زوال کا شکار ہو
جائیں تو پھر عالمی بدحالی کے مہیب سائے بنی نوع انسان کو گھیرے میں لے لیتے
ہیں.یہی اقتصادی بدحالی عالمی جنگوں اور عظیم تباہیوں کا راستہ ہموار کیا کرتی ہے.لوگ دیوالیہ ہو جاتے ہیں، کاروبار تباہ ہو جاتے ہیں، تجارتی سرگرمیاں ماند پڑ جاتی
ہیں، بے روزگاری کی شرح میں اضافہ ہونے لگتا ہے اور پراپرٹی یعنی جائیداد کا
کاروبار تباہ ہونے لگتا ہے.اس ساری صورت حال کے نتیجہ میں چاروں طرف جو
217
Page 230
مایوسیاں اور ناکامیاں پیدا ہوتی ہیں وہ بے گھر لوگوں کی تعداد میں اضافہ کر دیتی ہیں،
محرومیاں بڑھ جاتی ہیں، دھوکہ دہی اور جرائم میں اضافہ ہو جاتا ہے.اگر یہ سب کچھ
در حقیقت دنیا میں واقع ہو جاتا ہے تو کسی کو حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے خصوصاً
سرمایہ دارانہ نظام کے علمبرداروں کے لئے تو اس میں حیرت کی کوئی بات ہی نہیں
ہے.سرمایہ دارانہ نظام معیشت میں یہ صورت حال ان افراد تک ہی محدود نہیں رہتی
جنہیں اس قدر قرض دیا گیا ہو کہ واپس کرنا ان کی استطاعت سے باہر ہو جائے بلکہ
حقیقت یہ ہے کہ اس عمل سے سارے صنعتی مستقبل کو ایک حد تک فائدہ بھی ہوتا ہے.اپنے ملک میں تیار کی جانے والی مصنوعات کی قیمت کم کرنے میں مدد ملتی ہے اور
صارفین کے ہاتھوں میں دولت آ جانے سے ان کی قوت خرید میں اضافہ ہو جاتا
ہے.اس کا اثر قومی صنعت کی پیداواری صلاحیت پر پڑتا ہے.طلب میں اضافہ کے
نتیجہ میں پیداوار میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے اور اس طرح یہ اضافہ قیمتوں میں کمی کا
باعث بنتا ہے اور قومی صنعت عالمی منڈی میں بہتر مقابلہ کرنے کے قابل ہو جاتی
ہے.بظاہر یہ نظارہ بڑا ہی دلکش اور امید افزا نظر آتا ہے لیکن جلد ہی یہ حسین منظر
ایک خواب پریشان کا روپ دھار لیتا ہے.ایک وقت آتا ہے کہ سارا معاشرہ اپنی
بے صبری اور آمد سے بڑھ کر خرچ کرنے کے باعث بینکوں کے قرض میں جکڑا جاتا
ہے معاشرہ کی قوت خرید کم ہوتے ہوتے اپنی آخری حد تک پہنچ جاتی ہے.اس
صورت میں ملکی صنعت کے پاس اپنی بقا کے لئے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں رہتا کہ
وہ بیرونی منڈیاں تلاش کرے بصورت دیگر کوالٹی اور قیمتوں کے لحاظ سے دوسروں کا
مقابلہ نہیں کر سکتی.ملک کی اقتصادی بنیاد جس قدر چھوٹی ہو گی اسی قدر جلد صنعتی ترقی
کا سفر ایک ایسے مقام پر آ کر رک جائے گا جہاں سے آگے کوئی راستہ دکھائی نہیں
218
Page 231
دے گا.لیکن اگر معاشی بنیاد وسیع تر ہو گی تو اس سے صرف یہ فرق پڑے گا کہ آنے
والے اقتصادی بحران کا حقیقی احساس ذرا دیر سے ہوگا.آئیے ایک نظر ریاست ہائے متحدہ امریکہ پر ڈالتے ہیں کہ وہاں کیا ممکنہ
صورت حال ہو سکتی ہے.بلاشبہ امریکہ کی اپنی مارکیٹ ہی اتنی بڑی ہے جو اس کی
صنعت کو سہارا دے سکتی ہے یہاں تک کہ بعض ماہرین اقتصادیات کا خیال ہے کہ اگر
امریکہ باقی ساری عالمی برادری سے کٹ کر الگ بھی ہو جائے تو بھی اس کی اپنی
مارکیٹ کی وسیع بنیاد اس کی صنعت کی بقاء کے لئے کافی ثابت ہو گی.لیکن ایسے
ماہرین بعض دیگر متعلقہ عوامل کو نظر انداز کر دیتے ہیں.اگر آپ فرد واحد کی مذکورہ
بالا مثال کو امریکہ کی صورتحال پر چسپاں کریں تو آپ کو صاف دکھائی دینے لگے گا
کہ یہاں بھی منطقی انجام وہی ہوگا جس کا ذکر ہم پہلے ایک فرد کی مثال میں کر چکے
ہیں فرق صرف یہ ہے کہ یہاں معاشی تباہی میں کچھ وقت لگے گا.امریکی بجٹ کے بھاری خسارہ اور کھربوں ڈالر کے قرض کو دیکھا جائے تو معلوم
ہو جاتا ہے کہ امریکہ بحیثیت مجموعی پہلے ہی اپنی کل آمد سے زیادہ خرچ کر چکا ہے.امریکی عوام اپنے مستقبل سے لئے ہوئے بھاری قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے
ہیں.اب دو ہی صورتیں ہیں یا تو مجموعی طور پر قومی قوت خرید کم ہو جائے گی یا پھر
قرض دینے والے ادارے دیوالیہ ہو جائیں گے.فرد کی مثال میں ایک محدود
معیشت کا سوال تھا اور یہاں ایک وسیع تر معیشت ہمارے پیش نظر ہے.جہاں تک
قوانین قدرت کا تعلق ہے تو یاد رہے کہ ان قوانین سے کسی کو مفر نہیں کچھ بھی ہو یہ
بہر حال اپنا کام کرتے رہتے ہیں.پس یہ حالات جہاں بھی ہوں گے فطرت کے
قوانین اپنا کردار ضرور ادا کریں گے.گرمیوں کی شدت میں تالابوں اور جو ہڑوں کا پانی اپنے ماحول کے ساتھ ساتھ
219
Page 232
بہت جلد گرم ہو جاتا ہے مگر جھیلوں کا پانی گرم ہونے میں کچھ وقت لگتا ہے اسی طرح
چھوٹے سمندر بڑے سمندروں کی نسبت جلد گرم ہو جاتے ہیں.سورج کی تمازت
سے پانی کا درجہ حرارت بہر حال بڑھتا ہے یہ ایک ناگزیر اور اٹل قانون ہے فرق
صرف وقت کا ہے.بحر اوقیانوس کے پانیوں کو گرم ہونے میں اتنا زیادہ وقت لگتا ہے
کہ جب تک یہ پوری طرح گرم ہوتے ہیں اس کے ساحلوں پر واقع اکثر ممالک
میں موسم سرما کا آغاز ہو چکا ہوتا ہے.یہی وجہ ہے کہ ان ممالک کی آب و ہوا ان
ممالک کی نسبت معتدل ہے جو چھوٹے سمندروں کے گرد واقع ہیں.ملکوں کی معیشت
کا معاملہ بھی سمندروں کی طرح ہے.قرض لے کر خرچ کرنے کا فلسفہ بنیادی طور پر
اتنا ٹیڑھا اور غلط ہے کہ اس سے صحیح اور درست نتائج کی توقع رکھنا حماقت ہے.ایک اور اہم اور قابل توجہ امر یہ ہے کہ ترقی یافتہ اور صنعتی ممالک کی معیشت اور
صنعت کے زوال کا اثر غریب اور نسبتا کم ترقی یافتہ ممالک کی معیشت پر بھی پڑتا ہے
اور یہ ممالک بھی ایک مسلسل بڑھتے ہوئے مہیب خطرے کا شکار ہو جاتے ہیں.صنعتی ممالک کے سیاسی لیڈر ایک تو اپنی صنعت کو زوال سے بچانے کے لئے اپنی
برآمدات کو بڑھانا چاہتے ہیں دوسرے وہ اپنے عوام کا معیار زندگی بھی قائم رکھنا
چاہتے ہیں.ان ترقی یافتہ صنعتی ممالک کے سیاسی لیڈروں کی اپنی مجبوریاں ہیں.ایک تو ان کے عوام جدید سہولتوں کے عادی ہو چکے ہیں اور ان کا معیار زندگی اتنا بلند
ہو گیا ہے کہ اسے برقرار رکھنے کے لئے کئی پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں دوسرے یہ صنعت اپنی
بقا کے لئے زندگی کی تعیشات اور نئی سے نئی ایجادات کی تشہیر کرتی رہتی ہے جس سے
عوام کی آتش شوق اور بھی بھڑکتی ہے.نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بلند سے بلند تر معیار زندگی
کا مطالبہ بڑھتا چلا جاتا ہے.اس مطالبہ کے مسلسل دباؤ کے سامنے کوئی سیاسی حکومت
ٹھہر نہیں سکتی.220
Page 233
ایک طرف سیاسی رہنماؤں نے عوام کے بلند معیار زندگی کو قائم رکھنا ہوتا ہے اور
دوسری طرف انہیں یہ فکر دامن گیر ہوتی ہے کہ صنعتی زوال نہ ہو اور نظام معیشت چلتا
رہے پس ملکی مصنوعات کی فروخت کے لئے زیادہ سے زیادہ بیرونی منڈیاں تلاش کی
جاتی ہیں.ترقی یافتہ ممالک کے بلند معیار زندگی کو قائم رکھنے کے لئے تیسری دنیا کے
ممالک کا پہلے سے بڑھ کر خون چوسا جاتا ہے.روس اور مشرقی یورپ کے ممالک کو
اپنے معاشی نظام کی تشکیل نو کے لئے جو چیلنج درپیش ہیں وہ اور کیا ہیں؟ سابقہ
اشترا کی دنیا سے ابھرنے والے نئے سرمایہ دار ممالک کو بیرونی منڈیوں کی بڑھتی
ہوئی ضرورت آخر کیوں ہے؟ اور پھر مغربی ذرائع ابلاغ نے اپنی مصنوعات کی تشہیر
کے ذریعہ جس طرح تیسری دنیا اور سوشلسٹ ممالک کے مفلس و قلاش عوام کی
خواہشات اور تمناؤں کو بے چین اور مضطرب کر رکھا ہے کیا اس کا یہی مقصد تو نہیں
ہے؟ ان تمام عوامل کو یکجا کر کے دیکھیں تو معلوم ہو جائے گا کہ یہ حالات کرہ ارض پر
کسی مثبت تبدیلی کے آئینہ دار ہر گز نہیں ہیں.سود.امن کے لئے ایک خطرہ
قرآن کریم آج سے چودہ سو سال قبل اس عظیم تباہی کے متعلق خبر دار کر چکا ہے
جو سود پر مبنی معاشی نظام کی وجہ سے بالآخر بنی نوع انسان کے لئے مقدر ہو چکی ہے.یہ تنبیہ بڑی وضاحت سے اور بھر پور انداز میں ان آیات کریمہ میں موجود ہے.الَّذِينَ يَا كُلُوْنَ الرّبوا لَا يَقُومُونَ إِلا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَنُ مِنَ
الْمَسِ، ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبوا، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
ط -- وج
الربوا ، فَمَنْ جَاءَ ، مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرَهُ إِلَى الله.ج
لو
وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَبُ النَّارِ هُم فِيْهَا خَلِدُوْنَه يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبوا وَيَرْبِي
b
221
Page 234
الصَّدَقَتِ، وَاللهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارِ أَثِيمٍ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ و
أَقَامُوا الصَّلوةَ وَاتَوُ الزَّكوةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُم
يَحْزَنُونَ ، يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَابَقِيَ مِنَ الرِّبوا إِنْ كُنتُمْ
آرد
لله و
وہ وہ
0-600
مُّؤْمِنِينَ ، فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ ، وَ إِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ
ووه و
رء وسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَ إِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةِ فَنَظِرَةٌ إِلَى
مَيْسَرَةِ ، وَ أَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
تک وہ
°
(سورۃ البقرہ آیات ۲۷۶-۲۸۱)
ترجمہ :.وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں وہ کھڑے نہیں ہوتے مگر ایسے جیسے
وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان نے (اپنے) مسن سے حواس باختہ کر دیا
ہو.یہ اس لئے ہے کہ انہوں نے کہا یقیناً تجارت سود ہی کی طرح ہے
جب کہ اللہ نے تجارت کو جائز اور سود کو حرام قرار دیا ہے.پس جس کے
پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آ جائے اور وہ باز آ جائے تو جو
پہلے ہو چکا وہ اسی کا رہے گا اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے.اور جو
کوئی دوبارہ ایسا کرے تو یہی لوگ ہیں جو آگ والے ہیں.وہ اس میں
لمبا عرصہ رہنے والے ہیں.اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا
ہے اور اللہ ہر سخت ناشکرے (اور ) بہت گناہگار کو پسند نہیں کرتا.یقیناً
وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے اور انہوں نے نماز کو
قائم کیا اور زکوۃ دی ان کے لئے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے.اور ان پر کوئی خوف نہیں ہو گا اور نہ وہ غمگین ہوں گے.اے وہ لوگو جو
ایمان لائے ہو! اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو جو سود میں سے باقی رہ گیا ہے
اگر تم ( فی الواقعہ ) مومن ہو.اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ اور اس کے
رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو اور اگر تم تو بہ کرو تو تمہارے
222
Page 235
اصل زر تمہارے ہی رہیں گے.نہ تم ظلم کرو گے نہ تم پر ظلم کیا جائے گا.اور اگر کوئی تنگ دست ہو تو (اسے) آسائش تک مہلت دینی چاہئے اور
اگر تم خیرات کر دو تو یہ تمہارے لئے بہت اچھا ہے اگر تم کچھ علم رکھتے ہو.مذکورہ بالا آیات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انتباہ کیا گیا ہے اس کا مطلب ہے
ہے کہ سرمایہ دارانہ معاشرہ کو ان قوانین قدرت کے ذریعہ یقیناً سزا ملے گی جو
اللہ تعالیٰ کے جاری کردہ ہیں.اور ایسا اس وقت ہوگا جب وہ تمام عوامل جن کی بحث
اوپر گزر چکی ہے بالآخر انسان کو اقتصادی عدم توازن اور جنگ کی طرف لے جائیں
گے.یاد رہے کہ بدنظمی، فساد اور جنگیں ہمیشہ غرباء کے استحصال اور ان کے حقوق
غصب کرنے کے نتیجہ میں برپا ہوتی ہیں.اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے بارہ میں خبر دار کرنے کے معنی یہ ہیں
کہ ایسی ریاست جس کا سود پر دارو مدار ہو بالآ خر ضرور ایک ایسی صورت حال سے
دو چار ہو کر رہے گی جب قومیں جنگ کے لئے ایک دوسرے کے خلاف اٹھ کھڑی
ہوں گی.سود کے اس پہلو کو تفصیل سے بیان کرنے کی اس وقت گنجائش نہیں لیکن یہ
بتانا ضروری ہے کہ قرآن کریم نے جہاں بھی سود کی ممانعت کا ذکر کیا اس سے بعد کی
آیات میں ہمیشہ جنگ کا ذکر ہے.اس سے سود اور جنگ کے درمیان تعلق کی نشان
دہی ہوتی ہے.جو لوگ پہلی اور دوسری عالمی جنگ کے حالات سے واقف ہیں انہیں
یاد ہو گا کہ ان جنگوں کے آغاز کا ایک سبب سرمایہ دارانہ نظام تھا اور پھر انہیں طول
دینے میں بھی اس نظام نے تباہ کن کردار ادا کیا تھا.دولت کے انبار لگانے کی ممانعت
اسلام استحصال کی ہر شکل اور ہر قسم کے ناجائز ذرائع اختیار کرنے کو رد کرتا ہے
223
Page 236
مثلاً بے تحاشا دولت کا ارتکاز نیز چیزوں اور اجناس وغیرہ کی ذخیرہ اندوزی جس
سے قیمتیں رفتہ رفتہ بڑھتی چلی جاتی ہیں اور عام افراطِ زر اس کا آخری نتیجہ ہوا کرتا
ہے.قرآن کریم فرماتا ہے.يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ
بالْبَاطِل وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَالَّذِينَ يَكْبِرُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا
يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ : فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ
لا
ووه
و وہ ووه ووہ ووہ
بِهَا جِبَاههم وجنوبهم و ظهورهم ، هَذَا مَا كَنَرْتُمْ لَأَنْفُسِكُمْ
فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْثِرُونَ
ط
(سورۃ التوبہ آیات ۳۴-۳۵)
ترجمہ :.اے لوگو جو ایمان لائے ہو! یقیناً دینی علماء اور راہبوں میں سے
بہت ہیں جو لوگوں کے اموال ناجائز طریق پر کھاتے ہیں اور اللہ کی راہ
سے روکتے ہیں.اور جو لوگ سونا اور چاندی ذخیرہ کرتے ہیں اور انہیں
اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے
دے.جس دن جہنم کی آگ اس (سونے چاندی ) پر بھڑکائی جائے گی
پھر اس سے ان کی پیشانیاں اور ان کے پہلو اور ان کی پیٹھیں داغی
جائیں گی (اور کہا جائے گا) یہ ہے جو تم نے اپنی جانوں کے لئے جمع کیا
تھا.پس اسے چکھو جو تم جمع کیا کرتے تھے..اس کے باوجود اسلام نے فرد کو ہر جائز طریق پر دولت کمانے کی اجازت دی
ہے بشرطیکہ یہ طریق اور ذریعہ اسلام کے معاشی ضابطہ اخلاق سے مطابقت رکھتا ہو.مختصراً یہ کہ اسلام نے فرد کو ذاتی ملکیت اور نجی کاروبار کی اجازت دی ہے اور اس
کے اس بنیادی حق کو تسلیم کیا ہے.حکومتیں معیشت کی تشکیل کے وقت تمام تر توجہ اس
امر پر مرکوز رکھتی ہیں کہ معاشرہ کا ایک فرد اپنی روزی کس طرح کماتا ہے اس کی
آمدنی کتنی ہے، کاروبار میں منافع کی شرح کیا ہے، بکری کتنی ہوتی ہے، تنخواہ کتنی ملتی
224
Page 237
ہے.ہے.ان اعداد وشمار کی روشنی میں آمد پر ٹیکسوں کا تعین کیا جاتا ہے.یہ سب کچھ
کرنے کے بعد فرد کے مالی معاملات میں مزید بہت کم مداخلت کی جاتی
عام طور پر حکومتوں کی دلچسپی صرف فرد کی آمد تک محدود ہوتی ہے حکومت کو اس سے
کچھ سروکار نہیں ہوتا کہ فرد اپنی آمد یا ذخیرہ کی ہوئی دولت کو کس طرح خرچ کرتا
ہے.وہ چاہے تو اپنی دولت کو دریا میں بہا دے اور عیش وعشرت کو اپنا معمول بنالے
اور چاہے تو مالی آسودگی کے باوجود تنگی و ترشی سے زندگی بسر کرے.اپنے سرمائے کو
وہ جہاں چاہے اور جس طرح چاہے کام میں لائے ، حکومت اس میں کوئی مداخلت
نہیں کرتی.تا ہم مذہب فرد کی زندگی کے اس حصہ میں بھی نصیحت اور مشورہ کے رنگ میں
دخل دیتا ہے.مذہب صرف یہی نہیں بتاتا کہ روزی کس طرح کمانی چاہیے بلکہ
راہنمائی بھی کرتا ہے کہ اپنی کمائی کو کس طرح خرچ کرنا چاہئے اور کس طرح خرچ نہیں
کرنا چاہئے.لیکن یادر ہے کہ دولت کو خرچ کرنے کے متعلق مذہب کے اکثر احکامات
بنیادی طور پر اخلاقی اور روحانی فلاح و بہبود کے راہنما اصول ہیں.مثال کے طور پر
جب اسلام شراب نوشی ، جوئے یا حصول لذت کے دیگر ناجائز ذرائع پر خرچ کرنے
سے روکتا ہے تو خواہ اس کا براہ راست تعلق بجٹ سے نہ بھی ہو پھر بھی بالواسطہ ایسے
احکامات مذہب کی اخلاقی و روحانی تعلیمات کا حصہ ہیں.سرمایہ دارانہ نظام میں ایسے
احکامات کو فرد کی ذاتی زندگی اور اس کی اپنی مرضی سے خرچ کرنے کے حق میں
مداخلت تصور کیا جاتا ہے مگر یادر ہے کہ یہ سوچ اور یہ طرز عمل انسان کے لئے کوئی نئی
بات نہیں ہے.قرآن کریم سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ گزشتہ تہذیبوں اور قوموں نے
بھی مذہب کے متعلق اس قسم کے طرز عمل کا مظاہرہ کیا تھا.یہ بحث بار بار اٹھائی گئی کہ
مذہب کو لوگوں کے ذاتی معاملات میں مداخلت کا کیا حق ہے.قدیم زمانہ میں اللہ
225
Page 238
تعالیٰ کے ایک فرستادہ حضرت شعیب علیہ السلام نے جب مدین کے لوگوں کو یہ تعلیم
دینے کی کوشش کی کہ وہ کس طرح اپنی دولت کا بہترین استعمال کر سکتے ہیں اور انہیں کن
کن طریقوں سے بچنا چاہئے تو ان کی قوم نے انہیں مذمت کا نشانہ بنایا.قَالُوا يَشُعَيْبُ أَصَلوتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَّتْرَكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَّفْعَلَ فِي
أَمْوَالِنَا مَانَشَؤُا إِنَّكَ لَأَنْتَ الْعَلِيْمُ الرَّشِيدُه
(سورة هود آیت ۸۸)
ترجمہ:.انہوں نے کہا اے شعیب ! کیا تیری نماز تجھے حکم دیتی ہے کہ ہم
اسے چھوڑ دیں جس کی ہمارے باپ دادا عبادت کیا کرتے تھے یا ہم
اپنے اموال میں وہ (تصرف نہ ) کریں جو ہم چاہیں.یقیناً تو ضرور بڑا
بردبار ( اور ) عقل والا ( بنا پھرتا ) ہے.سادہ طرز زندگی
اسلام ایک سادہ طرزِ زندگی کو پیش کرتا ہے.فضول خرچی سے منع کرتا ہے مگر
دولت کو خرچ کرنے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے
ہے.وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا
مَحْسُورًا
( سورۃ بنی اسرائیل آیت ۳۰)
ترجمہ :.اور اپنی مٹھی ( بخل کے ساتھ ) بھینچتے ہوئے گردن سے نہ لگالے
اور نہ ہی اسے پورے کا پورا کھول دے کہ اس کے نتیجہ میں تو ملامت زدہ
(اور) حسرت زدہ ہو کر بیٹھ رہے.لک
وَاتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَلَا تُبَذِرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ
كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيطِيْنِ وَكَانَ الشَّيْطَنُ لِرَبِّهِ كَفُورًا
(سورۃ بنی اسرائیل آیات ۲۷.۲۸)
226
Page 239
ترجمہ.اور قرابت دار کو اس کا حق دے اور مسکین کو بھی اور مسافر کو بھی
مگر فضول خرچی نہ کر.یقیناً فضول خرچ لوگ شیطانوں کے بھائی ہیں اور
شیطان اپنے رب کا بہت ناشکرا ہے.شادی و بیاہ کے اخراجات
شادی بیاہ کی تقریبات جس انداز سے منعقد کی جاتی ہیں وہ امیر اور غریب
خاندانوں کے درمیان ایک حساس مسئلہ بن جاتا ہے.امراء کے ہاں ہونے والی
شان و شوکت دیکھ کر غریب والدین گہرے رنج وغم میں ڈوب جاتے ہیں خصوصاً جن
کی بیٹیاں شادی کی عمر کو پہنچ چکی ہوں ان کے اندر حسرت اور محرومی کی آگ بھڑ کنے
ہے.اسلام نے شادی بیاہ کی دعوتوں پر بے تحاشا خرچ کرنے اور اپنی امارت
اور ظاہری شان و شوکت کے مظاہرہ کی سخت مذمت کی ہے.ابتدائی تاریخ اسلام
سے پتہ چلتا ہے کہ شادی کی تقریبات اس قدر سادہ ہوا کرتی تھیں کہ اکثر لوگوں کو
بالکل بے رنگ اور بے رونق دکھائی دیتی تھیں.اگر چہ دیگر معاشروں کے
رسوم ورواج کے زیر اثر مسلمانوں کے ہاں بھی خصوصاً امراء کی شادیوں میں کئی
بدعات اور بد رسومات رفتہ رفتہ راہ پاگئی ہیں تاہم اب بھی بنیادی طور پر شادی کی رسمی
تقریب بالکل سادہ اور بے تکلف اور امیر وغریب سب کے لئے یکساں طور پر کم
خرچ ہے.شادی کا اعلان جو کہ نکاح کہلاتا ہے اکثر مساجد ہی میں کیا جاتا ہے جہاں
ہر کس و ناکس موجود ہوتا ہے امیر وغریب سب بلا امتیاز جمع ہوتے ہیں.مسجد کسی کی
شان وشوکت کے اظہار کی جگہ نہیں ہے بلکہ خدا کا گھر ہے جہاں اس کی عبادت کی
جاتی ہے.جہاں تک دعوتِ طعام اور شادی کے موقع پر خوشی اور مسرت کے اظہار کا
تعلق ہے امراء کو سخت تنبیہ کی گئی ہے کہ کوئی ایسی دعوت جس میں غرباء کو نہیں بلایا جاتا.227
Page 240
اللہ تعالیٰ کی نظر میں بدترین دعوت ہے.یہی وجہ ہے کہ ایک اسلامی معاشرہ میں ایسی
دعوتوں میں خوش پوش امراء کے درمیان معمولی اور سادہ کپڑوں میں ملبوس غرباء بھی
نظر آئیں گے جو آزادانہ سب سے مل رہے ہوں گے.غرباء کو یوں قریب سے دیکھ
کر ایک تو امراء کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور دوسرے غرباء کو یہ موقع میسر آتا ہے کہ
وہ امراء کے عمدہ کھانوں کا کچھ مزہ اٹھا سکیں.غرباء کی دعوت قبول کرنا
امراء اور سماجی لحاظ سے بلند مرتبہ اور معزز لوگوں کو یہ تاکید کی گئی ہے کہ اگر کوئی
انتہائی غریب اور مسکین شخص بھی انہیں اپنے گھر دعوت پر بلائے تو انہیں وہ دعوت قبول
کرنی چاہئے.بایں ہمہ اسے لازمی قرار نہیں دیا جا سکتا کیونکہ ان کے اپنے پہلے سے
طے شدہ پروگرام مصروفیات اور دیگر کئی مشکلات اس میں حارج ہوسکتی ہیں تاہم
آنحضرت ﷺ کا یہ دائی دستور تھا کہ آپ غریب ترین شخص کی دعوت کو بھی قبول فرما
لیا کرتے تھے.آپ سے محبت رکھنے والے آپ کے سب غلام جو امیر ہوں یا غریب
آپ کی اس نصیحت پر عمل کر کے بے حد خوشی اور فخر محسوس کرتے ہیں.اگر چہ آج کے
معاشرہ میں ایسی دعوتوں کو اس طرح قبول کرنے سے یہ تاثر بھی ابھر سکتا ہے کہ جیسے
امراء کے پاس سوائے دعوتیں کھانے کے اور کوئی کام ہی نہ ہو تا ہم ضروری ہے کہ
غرباء کی دعوت
کو کبھی کبھی قبول کر کے اس حکم کی روح کو زندہ رکھا جائے.پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ شراب نوشی اور جوا کو قرآن کریم نے ممنوع قرار دیا
ہے.خوشی کی تقریبات پر دولت لٹانے سے بھی روکا گیا ہے.بے تحاشا خرچ اور
ٹھاٹھ باٹھ کے ساتھ زندگی گزارنے کی جو مذمت کی گئی ہے وہ صرف شادی بیاہ کے
228
Page 241
مواقع سے ہی تعلق نہیں رکھتی بلکہ اس کا دائرہ ساری انسانی زندگی پر محیط ہے.اس
تعلیم کا حسن یہ ہے کہ اسے جبراً نافذ نہیں کیا جاتا بلکہ لوگوں کو پیار اور محبت کے ساتھ
سمجھا کر اس پر عمل کے لئے راغب کیا جاتا ہے.کھانے پینے میں اعتدال
يُبنى
آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا ج انه
لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ
(سورۃ الاعراف آیت ۳۲)
ترجمہ :.اے ابنائے آدم ! ہر مسجد میں اپنی زینت (ساتھ ) لے جایا کرو
اور کھاؤ اور پیو لیکن حد سے تجاوز نہ کرو.یقیناً وہ حد سے تجاوز کرنے
والوں کو پسند نہیں کرتا.دنیا میں بھوک کے خلاف ایک جہاد کی ضرورت ہے.وقت کی کمی کے باعث
اس موضوع پر یہاں تفصیل سے بات نہیں کی جاسکتی تاہم اس سلسلہ میں پہلا قدم تو یہ
ہے کہ خوراک کو ضائع ہونے سے بچایا جائے.اس موضوع پر میں مختصراً آگے چل کر
کچھ بیان کروں گا.قرض کا لین دین
اسلام اس امر کی بار بار تاکید کرتا ہے کہ بنیادی ضروریات زندگی کے لئے اور
ہنگامی حالات میں قرض لینا پڑ جائے تو وہ بلا سود یا قرضہ حسنہ کے طور پر ہونا چاہئے.صاحب استطاعت اور ذی ثروت لوگوں کا فرض ہے کہ وہ مالی مشکلات میں گھرے
ہوئے لوگوں کی مدد کریں.یہ امر بھی واضح کر دیا گیا ہے کہ اگر کوئی مقروض نا مساعد
229
Page 242
مالی حالات کی وجہ سے مقررہ وقت پر قرض لوٹانے کے قابل نہ ہو تو اسے مہلت ضرور
دی جانی چاہئے.قریبی رشتہ دار بھی اگر چاہیں تو قرض کی ادائیگی میں ہاتھ بٹا سکتے
ہیں.اگر مقروض وفات پا جائے تو اس کی متروکہ جائیداد سے قرض کی ادائیگی کی
جاسکتی ہے.مقروض کے بوجھ کو کم کرنے کے لئے زکوۃ کی رقم بھی استعمال میں لائی
جا سکتی ہے اور اگر ایک صاحب ثروت انسان کسی کا قرضہ معاف کر دیتا ہے تو
اللہ تعالیٰ کی نظر میں اور بھی اچھا عمل قرار پائے گا.تاہم ایسا مقروض جو ادائیگی قرض
کی استطاعت رکھتا ہے اسے بہر حال مقررہ مدت کے اندر اندر قرض واپس کر کے
ایفائے عہد کرنا چاہئے بلکہ اسے چاہئے کہ قرض لوٹاتے وقت بطور احسان کچھ زائد رقم
بھی ادا کر دے تاہم یہ زائد رقم دینا لازمی نہیں ہے اور نہ ہی پہلے سے اس کا تعین کرنا
چاہئے ورنہ ایسی ادائیگی سود کی وسیع تر تعریف کے زمرہ میں شامل ہو جائے گی.قرض کے متعلق قرآن کریم کی تعلیم مندرجہ ذیل آیات میں بیان کی گئی ہے.آرش
يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلا يَأْبَ كَاتِب " أَنْ يَكْتُ كَمَا عَلَّمَهُ اللهُ فَلْيَكْتُ
ص
ط
وَلْيُمْلِلِ الَّذِى عَلَيْهِ الْحَقَّ وَلْيَتَّقِ اللهَ رَبَّهُ وَلا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ، فَإِنْ كَانَ
الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهَا أَوْ ضَعِيفًا أَوْلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّه
٥٠٥
بِالْعَدْلِ ، وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ، فَإِنْ لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ
-٥
-٥
-٥
05
وامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلُّ إِحْدُهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدُهُمَا
الْأُخْرَى ، وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَادُعُوا ، وَلَا تَسْتَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ
كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا
أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَة تُدِيرُ ونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلا تَكْتُبُوهَا ،
وَأَشْهِدُوا إِذَاتَبَايَعْتُمْ ، وَلا يُضَارَ كَاتِب وَّلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ
28
ط
230
Page 243
فُسُوقٌ بِكُمْ ، وَاتَّقُوا اللهَ وَيُعَلِمُكُمُ اللهُ ، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۚ وَإِنْ
يْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبافَرِهن " مَقْبُوضَةٌ ، فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا
هو
فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَه وَلْيَتَّقِ اللهَ رَبَّهُ ، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ، وَمَنْ
تكْتُمْهَا فَإِنَّه، ايم " قَلبه ، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ
280-
( سورة البقرة آیات ۲۸۳ - ۲۸۴
اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو! جب تم ایک معین مدت تک کے لئے
قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو.اور چاہئے کہ تمہارے درمیان
لکھنے والا انصاف سے لکھے.اور کوئی کا تب اس سے انکار نہ کرے کہ وہ
لکھے.پس وہ لکھے جیسا اللہ نے اسے سکھایا ہے.اور وہ لکھوائے جس
کے ذمہ ( دوسرے کا ) حق ہے اور اللہ اپنے رب کا تقویٰ اختیار کرے
اور اس میں سے کچھ بھی کم نہ کرے.پس اگر وہ جس کے ذمہ ( دوسرے
کا ) حق ہے بیوقوف ہو یا کمزور ہو یا استطاعت نہ رکھتا ہو کہ وہ لکھوائے تو
اس کا ولی (اس کی نمائندگی میں) انصاف سے لکھوائے.اور اپنے
مردوں میں سے دو کو گواہ ٹھہرا لیا کرو.اور اگر دو مرد میسر نہ ہوں تو ایک
مرد اور دو عورتیں (ایسے) گواہوں میں سے جن پر تم راضی ہو.( یہ )
اس لئے (ہے) کہ ان دو عورتوں میں سے اگر ایک بھول جائے تو
دوسری اسے یاد کروا دے.اور جب گواہوں کو بلایا جائے تو وہ انکار نہ
کریں.اور (لین دین ) خواہ چھوٹا ہو یا بڑا اسے اس کی مقررہ میعاد تک
( یعنی مکمل معاہدہ) لکھنے سے اکتاؤ نہیں.تمہارا یہ طرز عمل اللہ کے
نزدیک بہت منصفانہ ٹھہرے گا اور شہادت کو قائم کرنے کے لئے بہت
مضبوط اقدام ہو گا اور اس بات کے زیادہ قریب ہو گا کہ تم شکوک میں
مبتلا نہ ہو.( لکھنا فرض ہے ) سوائے اس کے کہ وہ دست بدست تجارت
231
Page 244
ہو جسے تم (اسی وقت ) آپس میں لے دے لیتے ہو.اس صورت میں تم
پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اسے نہ لکھو.اور جب تم کوئی (لمبی) خرید و فروخت
کرو تو گواہ ٹھہرا لیا کرو.اور لکھنے والے کو اور گواہ کو (کسی قسم کی کوئی )
تکلیف نہ پہنچائی جائے.اگر تم نے ایسا کیا تو یقیناً یہ تمہارے لئے بڑے
گناہ کی بات ہوگی.اور اللہ سے ڈرو جب کہ اللہ ہی تمہیں تعلیم دیتا
ہے.اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھتا ہے.اور اگر تم سفر پر ہو اور تمہیں
کا تب میسر نہ آئے تو کوئی چیز با قبضہ رہن کے طور پر ہی سہی.پس اگر تم
میں سے کوئی کسی دوسرے کے پاس امانت رکھے تو جس کے پاس امانت
رکھوائی گئی ہے اسے چاہئے کہ وہ ضرور اس کی امانت واپس کرے اور
اللہ اپنے رب کا تقویٰ اختیار کرے.اور تم گواہی کو نہ چھپاؤ.اور جو
کوئی بھی اسے چھپائے گا تو یقیناً اس کا دل گہنگار ہو جائے گا.اور اللہ
اسے جو تم کرتے ہو خوب جانتا ہے.یہاں اس امر کا ذکر بے حد ضروری ہے کہ ازمنہ وسطی کی سوچ رکھنے والے علماء
نے ان آیات کو ان کے سیاق و سباق سے ہٹ کر کلیہ غلط معنوں میں استعمال کیا
ہے.وہ اس بات پر مصر ہیں کہ اسلام کی تعلیم کے مطابق ایک عورت کی گواہی کافی
نہیں ہے.ان کا موقف یہ ہے کہ ایک مرد کی گواہی کے مقابل ہر قانونی ضرورت
کے لئے دو عورتوں کی گواہی ضروری ہے.انہوں نے آیات کے بالکل غلط معنی
کرتے ہوئے اسلامی فقہ میں مرد اور عورت کی گواہی کے بارہ میں غلط تصور پیش کیا
ہے.ان کا خیال یہ ہے کہ جب قرآن کریم ایک مرد کو بطور گواہ طلب کرتا ہے تو اس
کا متبادل دو عورتوں کی گواہی ہوگی اور جہاں چار مرد گواہ چاہئیں وہاں گواہی دینے
کے لئے آٹھ عورتوں کی ضرورت ہو گی.یہ تصویر غیر حقیقی اور قرآنی تعلیمات سے
بہت دور ہے.نظام عدل کے اس مسئلہ پر از منہ وسطی کا سا تنگ نظر موقف دیکھ کر تو
232
Page 245
انسان پریشان ہو کر رہ جاتا ہے اس لئے ان آیات کے متعلق مندرجہ ذیل نکات
ضرور پیش نظر رہنے چاہئیں.ا.ان آیات میں مذکور دونوں عورتوں کو گواہی دینے کے لئے نہیں کہا گیا.۲.دوسری عورت کا کردار واضح طور پر معین اور محدود کر دیا گیا ہے.اس کی
حیثیت محض ایک مددگار کی ہے.۳.اگر دوسری عورت جو گواہی نہیں دے رہی پہلی عورت کی گواہی میں کوئی ایسی
بات دیکھتی ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہو کہ گواہی دینے والی خاتون نے سودہ اور معاہدہ
کی روح کو پوری طرح نہیں سمجھا تو وہ اس پر دوبارہ غور کرنے میں اس کی مدد کر سکتی
ہے یا اسے کوئی بھولی ہوئی بات یاد دلا سکتی ہے.۴.گواہی دینے والی عورت کو پورا اختیار دیا گیا ہے کہ اس کی اپنی گواہی
بہر حال ایک الگ آزاد حیثیت رکھے گی اور اگر وہ اپنی ساتھی سے متفق نہ ہو تو پھر
اس کا اپنا بیان ہی آخری اور حتمی متصور ہوگا.اس ضمنی بحث کے بعد اب ہم پھر اپنے اصل موضوع کی طرف واپس آتے ہیں.معاہدات کے سلسلہ میں اسلام کچھ پابندیاں عائد کرتا ہے.مثال کے طور پر مالی
لین دین کے متعلق معاہدات کے لئے ضروری ہے کہ طے شدہ شرائط کو گواہوں کی
موجودگی میں ضبط تحریر میں لایا جائے.ان شرائط کو قرض دار یا مشتری لکھوائے اور
طرفین اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر معاہدہ کو لفظاً ومعناً دیانتداری اور پوری شرائط
کے ساتھ نباہنے کی کوشش کریں.ظاہر ہے کہ ایسے نظام معیشت میں جہاں قرضہ حسنہ
کا رواج ہو وہاں سود پر لئے گئے غیر ضروری قرضوں اور ادھار کی بھر مار نہیں ہوگی
اور قرض دینے والا خواہ مخواہ لوگوں کو ادھار نہیں دے گا.اس کے نتیجہ میں فاضل
سرمایہ کا سیلاب نہیں آئے گا اور معاشرہ کی قوت خرید اپنی حقیقی وسعت اور اصل حدود
233
Page 246
کے اندر رہے گی اور مستقبل میں ملنے والی متوقع دولت کو آج ہی خرچ کرنے کا
رجحان خود بخود ختم ہو جائے گا.جو صنعت ایسی معاشی بنیادوں پر قائم ہوگی وہ لازماً
ٹھوس اور مضبوط ہو گی اور اس میں ہر قسم کے اقتصادی نشیب و فراز میں سے
ا
صحیح سلامت بیچ نکلنے کی صلاحیت بھی موجود ہوگی.مختصراً یہ کہ عوام کا سرمایہ امراء کے
ہاں گردش میں نہیں رہنا چاہئے بلکہ اس کا بہاؤ غرباء کی طرف ہونا چاہئے.اسلام
ایک سادہ طرز زندگی کو فروغ دیتا ہے کفایت شعاری اور جفا کشی سکھاتا ہے نہ کہ خشکی
اور زندگی کی لذات سے بے زاری.تا ہم یہ طرز تمدن کسی بھی طرح سے عیاشی
فضول خرچی اور ظاہری چمک دمک کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا.نہ ہی اس میں اس حد
تک دولت لٹانے کی اجازت ہے جس سے غرباء کی دل شکنی ہو اور وہ حسد کا شکار ہو
جائیں اور ان کے دل حسرتوں کی آماجگاہ بن جائیں اور یوں امراء اور غرباء کے
مابین فاصلہ اور بھی بڑھ جائے.معاشی طبقاتی فرق
یہ امر اچھی طرح سمجھ لینا چاہئے کہ دولت کے صرف چند ہاتھوں میں اکٹھا ہو
جانے سے معاشرہ میں مختلف طبقات پیدا نہیں ہو جاتے.طبقات سرمایہ کی اس تقسیم کی
وجہ سے وجود میں آتے ہیں جو مالک اور مزدور، جاگیر دار اور مزارع کے درمیان
ہوتی ہے.اس کے علاوہ بھی بہت سے عوامل ہیں جو طبقاتی اونچ نیچ پیدا کرتے ہیں.ان سب کا یہاں ذکر کرنا اور یہ بتانا تو ممکن نہیں کہ کس طرح یہ سب عوامل الگ الگ
اور مل کر طبقات پیدا کرنے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں تاہم بھارت کے مخصوص
روایتی معاشرہ کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات کھل کر سامنے آ جائے گی کہ ہزار ہا سال
میں پروان چڑھنے والا طبقاتی نظام کس طرح معرض وجود میں آتا ہے.ارتقاء کے
234
Page 247
اس طویل سفر میں صرف دولت کی تقسیم ہی اثر انداز نہیں ہوئی بلکہ کئی سماجی ، مذہبی اور
سیاسی عوامل بھی کار فرما رہے ہیں.بیرونی حملہ آوروں کا ایک طویل سلسلہ
اندرونی کشمکش، زندگی کی جدو جہد اور اپنا تسلط قائم کرنے کی کوششیں بھارت میں
پائے جانے والے ذات پات کے اس نظام کے پس منظر میں آج بھی صاف دکھائی
دے رہی ہیں.اور دراصل یہی وہ عوامل ہیں جنہوں نے بھارت میں اتنے طبقات کو
جنم دیا ہے.کارل مارکس نے اس صورت حال کو گہری نظر سے دیکھا ہے.نیو یارک
کے اخبار ہیرلڈ ٹریبیون (Herald Tribune) میں شائع ہونے والے خطوط میں
وہ ہندوستان کی معاشرتی صورت حال کو سائنٹیفک سوشلزم کے فلسفہ سے ہم آہنگ
خیال نہیں کرتا.اس نے بالآخر یہ نتیجہ نکالا ہے کہ ذات پات کے اس نظام کی
موجودگی میں ہندوستان کے متعلق غالب امکان یہی ہے کہ وہ اشتراکیت کی جانب
کبھی رخ نہیں کر سکے گا.اسلامی نقطہ نظر کے مطابق معاشرہ میں طبقات کی موجودگی اس وقت تکلیف دہ
صورت حال پیدا کر دیتی ہے جب دولت کے خرچ کے متعلق کوئی ضابطہ اخلاق موجود
نہ ہو.ایک ایسے معاشرہ کو تصور میں لائیے جہاں لوگوں کا رہن سہن سادہ ہے.لباس، خوراک یا رہائش وغیرہ پر بے جا اسراف سے کام نہیں لیا جاتا اور مختلف لوگوں
کے طرز زندگی میں کوئی نمایاں فرق نہیں ہوتا.وہاں چند ہاتھوں میں کتنی بھی دولت
کیوں نہ اکٹھی ہو جائے اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا البتہ دولت کے بے دریغ خرچ
اور اس کی نمود و نمائش اور دکھاوے سے دوسروں کے جذبات یقیناً مجروح ہوتے
ہیں.دولت بلا سوچے سمجھے لٹائی جا رہی ہو جہاں خرچ کرنا چاہئے وہاں خرچ نہ ہو اور
جہاں ضرورت نہیں وہاں دولت کا ضیاع ہو رہا ہو اس پس منظر میں جسم و جان کا رشتہ
برقرار رکھنے کی جدو جہد میں مصروف مصائب کے مارے ہوئے خستہ حال غرباء جب
235
Page 248
امراء کے ٹھاٹھ باٹھ اور ان کی شاہانہ طرز زندگی کو دیکھتے ہیں تو دولت کی یہ
غیر مساوی تقسیم ان کے مابین ایک ایسی خلیج پیدا کر دیتی ہے جسے پاٹا نہیں جاسکتا.پس اسلام فرد کی اس آزادی میں غیر ضروری طور پر دخل انداز نہیں ہوتا کہ وہ
دولت کمائے اور پس انداز کرے.اسلام تو پبلک سیکٹر سے زیادہ پرائیویٹ سیکٹر کی
حوصلہ افزائی کرتا ہے اور اسے فروغ دیتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسلام
طرز زندگی سے متعلق ایک معتین ضابطہ اخلاق بھی عطا کرتا ہے اور اگر اسے لفظاً ومعناً
اس کی حقیقی روح کے ساتھ اختیار کیا جائے تو بحیثیت مجموعی زندگی سب کے لئے سادہ
اور خوشگوار بن جائے.اسلامی نظام معیشت کے فلسفہ کا یہ پہلو چونکہ پہلے بیان ہو چکا
ہے اس لئے اس پر مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں.اسلام کا قانون وراثت
اسلام کا قانون وراثت بھی ایک شخص کی وفات کے بعد اس کے ترکہ کی
پسماندگان میں تقسیم کے سلسلہ میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے.ضروری ہے کہ
وراثت شریعت کے مقرر کردہ حصوں کے مطابق والدین، ازواج، اولاد،
رشتہ داروں اور دیگر عزیز واقارب میں تقسیم کی جائے.کسی وارث کو اللہ تعالیٰ کی
طرف سے دیئے گئے حقوق وراثت سے محروم نہیں کیا جا سکتا سوائے اس کے کہ کوئی
معقول وجہ ہو.وجہ کے درست یا غلط ہونے کا فیصلہ کوئی فرد واحد نہیں بلکہ (اسلامی
ریاست میں ) عدالت کرے گی.اگر کوئی شخص کسی دوسرے کے حق میں وصیت کرنا
چاہے تو وہ اپنی املاک کا زیادہ سے زیادہ ایک تہائی حصہ اپنی مرضی سے دوسرے
افراد یا سوسائٹی وغیرہ کو دے سکتا ہے.(دیکھیں سورۃ النساء آیات ۸ تا ۱۳)
دولت کے چند ہاتھوں میں ارتکاز کو روکنے کے لئے یہ اقدامات بہت مفید اور
236
Page 249
مؤثر ہیں.صرف بیٹے کا وارث ہونا، جائیداد کی کسی کے حق میں بھی وصیت نہ کرنا یا
موصی کے اختیارات کا لامحدود ہونا کہ وہ اپنی مرضی سے جو چاہے کرئے ان سب
باتوں کی اسلامی قانونِ وراثت میں ممانعت کر دی گئی ہے.اسی طرح منقولہ اور
غیر منقولہ دونوں قسم کی جائیداد نسلاً بعد نسل تقسیم در تقسیم ہوتی چلی جاتی ہے یہاں تک
که صرف تین چار نسلوں ہی میں بہت بڑی بڑی جائیدادیں بھی تقسیم کے بعد سکٹر کر رہ
جاتی ہیں.نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ زمین کی ملکیت بٹ جانے سے ہر قسم کی اجارہ داری ختم
ہو جاتی ہے اور معاشرہ دائمی طبقاتی تقسیم کا شکار نہیں ہونے پاتا.رشوت کی ممانعت
وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (سورة البقرة آیت ۱۸۹)
ترجمہ :.اور اپنے ہی اموال اپنے درمیان جھوٹ فریب کے ذریعہ نہ
کھایا کرو.اور نہ تم انہیں حکام کے سامنے (اس غرض سے ) پیش کرو کہ
تم گناہ کے ذریعہ لوگوں کے (یعنی قومی ) اموال میں سے کچھ کھا سکو
حالانکہ تم (اچھی طرح) جانتے ہو.مضمون کے اس پہلو کو فی الحال مجھے چھوڑنا پڑے گا تاہم یہ پہلو جو بد عنوانی اور
رشوت وغیرہ کی شکل میں خاص طور پر تیسری دنیا کے ممالک میں نظر آتا ہے
انفرادی امن کے ذکر میں دوبارہ زیر بحث آئے گا.تجارتی ضابطہ اخلاق
اسلام نہ تو سرمایہ دارانہ نظام کو کلیتہ رد کرتا ہے اور نہ سائینٹیفک سوشلزم کو بالکل
237
Page 250
مسترد کرتا ہے.اسلام کے اقتصادی نظام میں دونوں کی خوبیاں شامل ہیں.اسلام
نے آج سے چودہ سو سال پہلے جو مکمل ضابطۂ اخلاق لین دین اور تجارت کے متعلق
دیا تھا اس کے کچھ اصولی پہلو درج ذیل ہیں.آج جدید دور کا انسان بالآخر بڑے
تلخ تجربات اور مشکلات کے بعد ان اصولوں کو دریافت کر سکا ہے.ا.اسلام میں تجارتی تعلقات کامل اعتماد اور دیانتداری پر مبنی ہیں.( سورة البقرة آیات ۲۸۴٬۲۸۳)
۲.اسلام غلط اوز ان رکھنے اور کم ماپ تول سے منع کرتا ہے.( سورة المطففین آیات ۲ تا ۴)
ناقص مال اور خراب اشیاء فروخت کرنے سے تاجروں کو منع کیا گیا ہے یعنی
ایسی چیزیں جو گل سڑ چکی ہوں یا ناکارہ ہو چکی ہوں.تاجر کو کوئی چیز فروخت کرتے
ہوئے اس کا نقص چھپانے کی ہرگز کوشش نہیں کرنی چاہئے.(صحیح مسلم) اگر کوئی ایسی
ناقص چیز فروخت کی جاتی ہے جس کے نقص کا خریدار کو پہلے سے علم نہیں تھا وہ علم
ہونے پر اس چیز کو واپس کرنے اور اپنی رقم واپس لینے کا اختیار رکھتا ہے.۴.تاجر کو مختلف گاہکوں سے مختلف نرخ وصول کرنے سے منع کیا گیا ہے تا ہم وہ
اپنی صوابدید پر کسی بھی گاہک کو رعایتی قیمت پر کوئی چیز فروخت کر سکتا ہے.اس سلسلہ
میں وہ کوئی بھی مناسب قیمت مقرر کرنے کا مجاز ہے.(صحیح بخاری و صحیح مسلم )
۵.اسلام تجارت میں جعلی مقابلہ کو منع کرتا ہے.مختلف کاروباری فر میں باہم
گٹھ جوڑ کر کے پیداوار اور مارکیٹ پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتی ہیں اور باہمی طور پر
مقابلہ نہ کرنے کا فیصلہ کر لیتی ہیں.اسلام ایسی گروہ بندیوں کی سختی سے ممانعت کرتا
ہے.نیلامی میں جھوٹ موٹ کی بولیاں دے کر امکانی خریدار کو دھوکہ دینے سے بھی
منع کیا گیا ہے.(صحیح بخاری و صحیح مسلم ).اسی طرح اسلام ہدایت کرتا ہے کہ اشیاء کی فروخت کھلے عام اور ترجیحاً
238
Page 251
گواہوں کی موجودگی میں کی جائے.نیز خریدار کو لاعلمی میں نہ رکھا جائے.اسے
پوری طرح باخبر کر دیا جائے کہ وہ کیا خرید رہا ہے.( صحیح مسلم)
مختصر یہ کہ اسلام کی کوشش اور حکمت عملی یہ ہے کہ امیر اور غریب کے مابین فاصلہ
کو کم کیا جائے.چنانچہ اس کے لئے وہ مندرجہ ذیل اقدامات کرتا ہے.ا.بعض چیزوں کی سرے سے ممانعت کر دی گئی ہے.مثلاً شراب نوشی اور جوا
وغیرہ جس کا ذکر پہلے گزر چکا ہے.۲.سود کے ذریعہ دولت کے انبار لگانے سے منع کر دیا گیا ہے.۳.نجی کاروبار کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے.۴.دولت کی گردش کو تیز کر دیا گیا ہے.۵.غریبانہ اور سادہ طرز زندگی اختیار کرنے کی تعلیم دی گئی ہے اور اس کے لئے
بار بار تلقین اور نصیحت کی گئی ہے.انسان کی طبعی شرافت سے یہ توقع رکھی گئی ہے کہ وہ
با وجود صاحب حیثیت ہونے کے اپنی زندگی کے انداز کو اتنا سادہ اور معیار کو اس سطح
پر رکھے گا جو غرباء کی پہنچ سے اس قدر دور نہ ہو کہ وہ اس کا خواب بھی نہ دیکھ سکیں.اس تمام تر تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ دل میں دوسروں کے جذبات کا احساس اور
احترام پیدا ہو اور اگر کہیں بہیمیت اور دوسروں پر ظلم کرنے کا رجحان پایا جائے تو اس
کا گلا گھونٹ دیا جائے.اس تعلیم میں جھوٹے تکبر، منافقت، سطحیت ، دنیا پرستی،
فخر و مباہات اور دوسروں کو کم تر سمجھنے اور اس قسم کی دیگر برائیوں کے خلاف حقیقی
معنوں میں ایک مقدس جنگ اور جہاد کا اعلان کیا گیا ہے اور انسان کے اندر جو
تہذیب، شائستگی اور شرافت ہے اسے ابھارا گیا ہے اور دوسروں کی تکالیف کا احساس
دلایا گیا ہے.عموں اور دکھوں کے مارے ہوئے ان لوگوں کو دیکھ کر جو بمشکل اپنا
پیٹ بھر سکتے ہیں انسان کو بعض اوقات عیش وعشرت کی زندگی گزارتے ہوئے جرم کا
239
Page 252
سا احساس ہونے لگتا ہے.مانا کہ اس قسم کی عظیم انسانی اقدار کے علمبردار اور ایسے
اعلیٰ درجہ کے تہذیب یافتہ لوگ بہت کم ہوا کرتے ہیں لیکن اس تعلیم کے نفاذ سے
معاشرہ میں دوسروں کی بھلائی کا مجموعی شعور اور احساس اتنا بڑھ جاتا ہے کہ یہ ممکن
ہی نہیں رہتا کہ انسان کو صرف اپنی ضروریات اور عیش وعشرت کی پڑی رہے اور
معاشرہ کے کم نصیب لوگوں کی حالت زار کی طرف توجہ ہی نہ کی جائے.اسلام کی
تعلیم مطالبہ کرتی ہے کہ زندگی سے لوگوں کا تعلق محض اپنی ذات کی حد تک ہی محدود نہ
رہے بلکہ انہیں گردو پیش کے حالات سے باخبر رہتے ہوئے زندگی گزارنے کا ڈھب
بھی آ جائے اور وہ اس وقت تک چین سے نہ بیٹھ سکیں جب تک لوگوں کے دکھ درد کم
کرنے اور ان کے معیار زندگی کو کسی قدر بہتر بنانے کے لئے کچھ کام نہ کر لیں.مومنین کے ایسے معاشرہ کی خصوصیات قرآن کریم کی ایک ابتدائی آیت میں
بیان ہوئی ہیں جس کا اس خطاب میں پہلے بھی حوالہ دیا جا چکا ہے.اللہ تعالیٰ فرماتا
ہے:
ت ٥٠٠اوہ وہ وہ
وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنْفِقُونَO
( سورة البقرة آیت ۴)
ترجمہ.اور جو کچھ ہم انہیں رزق دیتے ہیں اس میں سے خرچ کرتے ہیں.بنیادی ضروریات زندگی
معاشرتی اور اقتصادی امن کے ضمن میں بتایا جا چکا ہے کہ غرباء اور ضرورتمندوں
کو صدقات دینے کے تصور کو اسلام نے کس طرح یکسر تبدیل کر دیا ہے.قومی اموال
میں جہاں تک افراد کے حقوق کا سوال ہے قرآن کریم نے اس سلسلہ میں ایک کسوٹی
بیان کی ہے جس کے ذریعہ ہم یہ پرکھ سکتے ہیں کہ کتنی دولت عام آدمی کو ملنی چاہئے تھی
جو چند سرمایہ داروں کے ہاتھوں میں اکٹھی ہو گئی ہے.240
Page 253
وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٍ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ
( سورة المعارج آیات ۲۵-۲۶)
ترجمہ:.اور وہ لوگ جن کے اموال میں ایک معین حق ہے مانگنے والے
کے لئے اور محروم کے لئے.ان آیات میں امراء مخاطب ہیں.انہیں یاد دلایا گیا ہے کہ ان کی دولت کا یقیناً
ایک حصہ ایسا ہے جو دراصل فقراء اور غرباء کا ہے اور وہی اس کے حقدار ہیں.یہ
اندازہ کیسے کیا جائے کہ چند امیر لوگوں نے غرباء کے حقوق پر قبضہ کر لیا ہوا ہے جس
کے نتیجہ میں معاشرہ عدم توازن کا شکار ہو چکا ہے.اس صورت حال کو جانچنے کا پیمانہ
وہ حقوق ہیں جن کی اسلام ضمانت دیتا ہے.اسلامی تعلیم کے مطابق انسان کی چار
بنیادی ضروریات زندگی ہیں جو بہر حال پوری ہونی چاہئیں.قرآن کریم فرماتا ہے.إِنَّ لَكَ اَلا تَجُوْعَ فِيهَا وَلَا تَعرى وَأَنَّكَ لَا تَظْلَمُوا فِيهَا وَلَا تَضْحى
(سورۃ طہ آیات ۱۱۹.۱۲۰)
ترجمہ:.تیرے لئے مقدر ہے کہ نہ تو اس میں بھوکا رہے اور نہ نگا.اور
یہ ( بھی ) کہ نہ تو اس میں پیاسا رہے اور نہ دھوپ میں جلے.پس اسلام نے ان چار نکات پر مشتمل ایک ایسا چارٹر دیا ہے جس میں بنیادی
ضروریات زندگی کے تعین اور تعریف کے بعد ان کو کم سے کم حقوق کے طور پر شرعاً
قائم فرما دیا گیا ہے.اور یہ وہ حقوق ہیں جن کو پورا کرنا حکومت کا فرض قرار دیا گیا
ہے.یعنی:
(۱) خوراک (۲) لباس (۳) پانی (۴) رہائش
دوسرے ممالک کا تو کیا ذکر خود برطانیہ اور ریاستہائے متحدہ امریکہ میں بھی
لاکھوں لوگ ایسے ہیں جن کے پاس سر چھپانے کے لئے بھی جگہ نہیں ہے بلکہ ایسے
241
Page 254
بھی ہیں جنہیں اپنی بھوک مٹانے کے لئے کوڑے کے ڈھیروں پر سے بچا کھچا کھانا
تلاش کرنا پڑتا ہے.ان فتیح مناظر کو دیکھ کر سرمایہ دارانہ معاشرہ کی فطری کمزوریاں
بے نقاب ہو جاتی ہیں اور اس گہرے پوشیدہ مرض کا پتہ چلتا ہے جو اسے اندر ہی اندر
کھائے جا رہا ہے.مادہ پرستی اپنی انتہائی شکل میں خود غرضی کو پروان چڑھاتی ہے اور دوسروں کی
تکلیف کے احساس سے عاری کر دیتی ہے.بلاشبہ تیسری دنیا کے اکثر ممالک میں
انتہائی غربت کے باعث اس سے بھی زیادہ درد ناک مناظر دکھائی دیتے ہیں.لیکن
اول تو وہاں سارے کا سارا معاشرہ غربت کا شکار ہے اور دوسرے یہ کہ یہ ممالک بھی
سرمایہ دارانہ نظام کی ڈگر پر چلائے جا رہے ہیں.ایسے ممالک کی اکثر آبادی عیسائی
ہو یا یہودی، ہندو ہو یا مسلمان یا لامذہب، سب کا نظام اقتصادیات بنیادی طور پر
سرمایہ دارانہ نظام سے مختلف نہیں ہے.دنیا کے نام نہاد ترقی یافتہ ممالک میں موجود تنگ و تاریک آبادیاں انسانیت کے
چہرہ پر ذلت کے بدنما داغ ہیں.ان آبادیوں میں بدی پروان چڑھتی ہے اور جرائم
بڑھتے چلے جاتے ہیں.براعظم افریقہ کے ممالک اور دیگر ممالک میں ایسے خطے بھی
ہیں جہاں لوگوں کی ایک بڑی تعداد کو دور دور تک پینے کا صاف پانی تک میسر نہیں
ہے.ان علاقوں میں آپ کو اگر ایک وقت بھی پیٹ بھر کر کھانا مل جاتا ہے تو آپ
اپنے آپ کو خوش قسمت خیال کرتے ہیں.پانی کی نایابی ایک روزمرہ کا مسئلہ ہے
دوسری طرف دنیا میں ایسے ممالک بھی ہیں جن کے پاس وہ تمام ذرائع اور وسائل
موجود ہیں جن سے محض چند سالوں میں ان غریب ممالک کی تقدیر بدلی جاسکتی ہے
اور اس کے ساتھ ساتھ امیر ممالک کے خزانوں میں بھی کوئی کمی نہیں ہو گی.لیکن
افسوس تو یہ ہے کہ انہیں خیال تک نہیں آتا کہ وہ اپنے ان خزانوں میں سے کچھ حصہ
242
Page 255
ان غریب ممالک کے لئے بھی مختص کریں جس سے ان لاکھوں کروڑوں انسانوں کے
دکھ درد اور مصائب کا مداوا کیا جا سکے.اسلامی نقطہ نظر سے یہ موضوع بڑا اہم ہے.اسلام کے نزدیک فرد کی مصیبت کے وقت اس کی مدد کے لئے اس ملک کا معاشرہ ہی
ذمہ دار نہیں بلکہ کسی بھی معاشرہ کے مصیبت میں گرفتار انسان کی تکلیف کے ازالہ کی
ذمہ داری تمام بنی نوع انسان پر عائد ہوتی ہے اور اس ذمہ داری کی ادائیگی کے لئے
ہر انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے جوابدہ ہے.انسانیت کا مرتبہ جغرافیائی حدود،
رنگ ونسل اور مذہبی و سیاسی عقائد سے بالا ہے.لوگ جب بھی اور جہاں بھی قحط،
بھوک یا دوسری قدرتی آفات کا شکار ہوں تو اسے ایک انسانی مسئلہ سمجھا جانا چاہئے
اور ہر ملک اور ہر معاشرہ کو ان دکھوں کو کم کرنے کے لئے مدد دینی چاہئے.یہ ایک
قابل شرم بات ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی تمام تر ترقی کے باوجود دنیا سے بھوک
اور پیاس ختم نہیں کی جاسکی.وجہ یہ ہے کہ اس طرف جتنی توجہ دی جانی چاہئے تھی
نہیں دی گئی.کوئی ایسا نظام ضرور وضع ہونا چاہئے جس کے ذریعہ تمام ممالک سے
اکٹھی کی ہوئی دولت فوری طور پر ان علاقوں میں تقسیم کی جا سکے جہاں بھوک نے
ڈیرے ڈال رکھے ہوں اور قحط کے ہاتھوں انسان لقمہ اجل بن رہے ہوں یا جہاں
لوگ بالکل بے زر اور بے گھر ہو چکے ہوں.حکومت کی ذمہ داریاں ملکی اور قومی بھی ہیں اور عالمی بھی.قومی سطح پر حکومت کی
ذمہ داری تو یہ ہے کہ ہر فرد کی بنیادی ضروریات پوری کی جائیں اور اس امر کو یقینی
بنایا جائے کہ بلا استثناء سب کو کھانا تن ڈھانپنے کو لباس، پینے کو پانی اور سر چھپانے کو
جگہ میسر ہو.عالمی ذمہ داریاں (جن کا ذکر آگے آئے گا) یہ ہیں کہ انسانیت پر
نازل ہونے والی آفات کا مقابلہ کرنے کے لئے مرکزی فنڈ کے قیام اور دیگر وسائل
کو اکٹھا کرنے میں بھر پور حصہ لیا جائے.قدرتی آفات ہوں یا انسان کے ہاتھوں
243
Page 256
انسان پر توڑے جانے والے مصائب یہ ایک عالمی ذمہ داری ہے کہ ان ممالک کی
مدد کی جائے جو ایسے بحرانوں سے بخوبی نبرد آزما ہونے کی طاقت نہ رکھتے ہوں.اصلاح احوال کی خاطر حکومت کا یہ فرض ہے کہ جو کچھ درحقیقت غرباء اور فقراء کی
ملکیت ہے وہ ان کو واپس منتقل ہوتا کہ وہ بھی مناسب رنگ میں زندگی گزار سکیں.اس سلسلہ میں چار بنیادی ضروریات یعنی خوراک لباس، پانی اور رہائش کو دوسری تمام
چیزوں پر ترجیح حاصل ہوگی.بالفاظ دیگر ایک حقیقی اسلامی ریاست میں کوئی نادار اور
محتاج ایسا نہیں ہو سکتا جسے بھیک مانگنے کی ذلت اٹھانی پڑے اور جس کی یہ چار بنیادی
ضروریات پوری نہ ہوں.اگر ان ضروریات کے پورا ہونے کی ضمانت مل جائے تو
حکومت اپنی کم سے کم ذمہ داری کی ادائیگی سے عہدہ برآ ہو جائے گی.اگر چہ
بحیثیت مجموعی معاشرہ کی دیگر ذمہ داریاں اس سے کہیں زیادہ ہیں.یہ قول کہ انسان صرف روٹی سے نہیں جیتا اپنے اندر بڑے گہرے معانی رکھتا
ہے.اس کی روشنی میں مذکورہ بالا بنیادی ضروریات صاف اور صحت بخش پانی،
مناسب لباس اور مناسب رہائش میں تبدیل ہو جاتی ہیں.تاہم یہ تمام ضروریات
پوری ہونے سے بھی زندگی مکمل نہیں ہوتی.انسان ہمیشہ ان بنیادی ضروریات سے
بڑھ کر کسی اور چیز کی تلاش میں رہتا ہے.پس ضروری ہے کہ معاشرہ غرباء کی
بے کیف زندگیوں میں رنگ بھرنے کے لئے کوئی مناسب اور مؤثر قدم اٹھائے اور
امراء کی خوشیوں میں انہیں بھی حصہ دار بنائے.پھر صرف یہی کافی نہیں کہ معاشرہ
کے خوش نصیب اور امیر لوگ اپنی دولت میں سے غرباء کو ان کا حصہ لوٹا دیں بلکہ
ضروری ہے کہ وہ غربت کے ان دکھوں میں بھی ان کے شریک ہوں جن میں
انسانوں کی ایک بہت بڑی تعداد مبتلا ہے اور سسک سسک کر زندگی کے دن پورے
کر رہی ہے.لازماً ایسا انتظام ہونا چاہئے جس کے ذریعہ امراء اور غرباء باہم گھل مل
244
Page 257
سکیں.اونچے طبقہ سے تعلق رکھنے والے امراء بخوشی نچلے طبقہ کے لوگوں سے ملیں
تا کہ وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں کہ غربت میں زندگی کاٹنے کے کیا معنی ہوتے
ہیں.اسلام کئی ایسے اقدامات کرتا ہے جن سے یہ ناممکن ہو جاتا ہے کہ معاشرہ الگ
الگ طبقات میں اس طرح تقسیم ہو جائے کہ ان کا کوئی باہم رابطہ ہی نہ رہے اور وہ
ایک دوسرے سے کٹ کر رہ جائیں.ان اقدامات میں سے بعض کا مختصر ذکر پہلے کیا
جا چکا ہے چند ایک کا ذکر اب کیا جائے گا.عبادت.معاشرتی وحدت کا ایک ذریعہ
(۱) شروع ہی میں یہ اقرار کہ خدا ایک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے
خالق اور مخلوق میں وحدت کے رشتہ کو قائم کرتا ہے اور خالق کا ایک ہونا مخلوق میں
وحدت پیدا کرنے کا ذریعہ ہے.(۲) روزانہ پانچ وقت کی نماز با جماعت وحدت پیدا کرنے کا شاید مؤثر ترین
ذریعہ ہے.امیر اور غریب، چھوٹے اور بڑے بلا استثناء سب کو مسجد میں نماز ادا
کرنے کا حکم ہے.اگر چہ سب کے لئے مساجد تک پہنچنا ممکن نہیں ہوتا تاہم
مسلم معاشرہ میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد جو مسجد تک پہنچ سکتی ہے ان پر اس حکم کی
پابندی کرنا فرض ہے.باقاعدہ پانچ نمازیں روزانہ باجماعت ادا کرنے والوں کی
تعداد مختلف ممالک میں کم و بیش ہو سکتی ہے.تاہم مسلمانوں کی اکثریت کو مساجد میں
آ کر نمازیں ادا کرنے کا موقع ضرور ملتا ہے.نماز کا یہ نظام بذات خود مساوات
انسانی کا ایک عظیم پیغام ہے.مسجد میں پہلے پہنچنے والا جہاں چاہے بیٹھے اور بعد میں
آنے والا کوئی شخص خواہ وہ معاشرہ میں کتنا ہی بلند مرتبہ کیوں نہ ہو پہلے آنے والے کو
اس کی جگہ سے اٹھانے کا سوچ بھی نہیں سکتا.نماز کے وقت تمام لوگ کندھے سے کندھا
245
Page 258
ملا کر یوں صف بستہ ہو جاتے ہیں کہ ان کے درمیان کوئی خلا نہیں رہتا.بہترین لباس
میں ملبوس شخص کے پہلو میں ایک اور نمازی پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے نماز ادا کر
رہا ہوتا ہے.زرد چہروں والے نحیف و نزار لوگ اور صحت مند و توانا لوگ روزانہ
پانچ بار ایک ایسی جگہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں جہاں سب برابر ہوتے ہیں اور
جہاں سے ہمیشہ اور بار بار اللہ اکبر کا پیغام دیا جاتا ہے.اپنے علاقہ کے افراد سے
بار بار مل کر اور لوگوں کے دکھ درد کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر نسبتا آرام و آسائش کی
زندگی بسر کرنے والے کا دل متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا.اس طرح اسے یہ احساس
ہوتا ہے کہ لوگوں کی تکالیف کو کم کرنے اور ان کے معیار زندگی کو بہتر بنانے کے لئے
ضرور کچھ کرنا چاہئے.اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ کی
عزت کم ہو جائے گی بلکہ آپ خود اپنی نظروں میں گر جائیں گے.اس با ہمی رابطہ اور میل جول میں ہر جمعہ کے دن اور بھی اضافہ ہو جاتا ہے.اس
روز تمام مسلمان ایک مرکزی مسجد میں اکٹھے ہوتے ہیں اور یوں غریب آبادیوں کے
رہنے والوں اور امیر علاقوں کے لوگوں میں رابطہ پیدا ہوتا ہے.سال میں دو عیدوں
کے موقع پر یہ رابطہ وسیع تر ہو جاتا ہے.عید الفطر سے پہلے غرباء کی مدد کے لئے
فطرانہ دیا جاتا ہے جو ایک طوعی چندہ ہے.(۳) رمضان کا مہینہ امراء اور غرباء کو ایک بار پھر ایک ہی صف میں لا کھڑا کرتا
ہے.اس مہینہ میں امراء بھی بھوک اور پیاس کی شدت برداشت کرتے ہیں اس
طرح انہیں ان بے شمار لوگوں کی یاد دلائی جاتی ہے بھوک اور پیاس جن کی زندگی کا
معمول ہے.(۴) زکوۃ کے ذریعہ امراء کی دولت میں سے غرباء کا حق انہیں منتقل ہو جاتا
ہے.246
Page 259
(۵) اسلام کا پانچواں رکن حج ہے.عموماً حج کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ وحدت
انسانی کا عظیم ترین اظہار ہے.حج میں خواتین کو بالکل سادہ سفید رنگ کے سلے ہوئے
کپڑے پہنے کی اجازت ہوتی ہے جبکہ مرد صرف دوان سلی سفید چادریں اوڑھتے
ہیں.امیر و غریب سب کے لئے یہی ایک لباس مقرر ہے.اسی پر بس نہیں مذکورہ بالا
عبادات کے علاوہ مسلمان معاشرہ میں اور بھی بہت سے ایسے مؤثر اقدامات کئے گئے
ہیں جن کے ذریعہ مختلف طبقات کے درمیان فاصلہ کم سے کم تر ہوتا چلا جاتا ہے.اس
طرح ایک صحت مند ماحول کی خاطر باہمی رابطہ اور میل ملاپ کی اشد ضرورت پوری
ہوتی رہتی ہے اور معاشرہ گھٹن کا شکار نہیں ہونے پاتا.اس صحت مند معاشرہ میں امراء
کو یہ اجازت تو ہے کہ وہ مناسب حدود میں رہتے ہوئے اپنی امارت سے بہرہ مند
ہوں لیکن ساتھ ہی انہیں غرباء کی دیکھ بھال کا حکم بھی دیا گیا ہے.حضرت مسیح علیہ السلام کے اس قول میں کہ” کمزور اور عاجز زمین کے وارث
ہوں گے اس اصول کی تشریح کی گئی ہے.یہ ایک افسوسناک صورت حال ہے کہ
اس اخلاقی تعلیم کے باوجود سرمایہ دارانہ نظام معاشرہ کے کمزور اور غریب افراد کی
دیکھ بھال میں ناکام رہا ہے.عالمی ذمہ داریاں
اگر کوئی معاشرہ کسی قدرتی آفت یا مصیبت کا شکار ہو جائے تو اس صورت میں
اس کی کس طرح اور کیا کیا مدد کی جا سکتی ہے (دیکھیں بنیادی ضروریات زندگی کی
مذکورہ بالا بحث) قرآن کریم مندرجہ ذیل ترتیب سے اس کا ذکر فرماتا ہے:
رقبة أَوْ إِطْعَمْ فِي يَوْمٍ ذِى مَسْغَبَةٍ يَّيْمَا ذَا مَقْرَبَةِ أَوْ مِسْكِينَا
ذَا مَتْرَبَةِ
247
(سورۃ البلد آیات ۱۴ تا ۱۷)
Page 260
ترجمہ:.گردن کا آزاد کرنا.یا ایک عام فاقہ والے دن میں کھانا
کھلانا.ایسے یتیم کو جو قرابت والا ہو یا ایسے مسکین کو جو خاک آلودہ ہو.بالفاظ دیگر صحیح ترجیحات یہ ہوں گی :
(1) ان آیات میں بنی نوع انسان کی اس حقیقی اور سچی خدمت کا ذکر ہے جو
اللہ تعالیٰ کے حضور قبول کی جاتی ہے.سب سے بڑھ کر تو وہ لوگ مدد کے محتاج ہیں جو
غلامی کی سی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں یعنی قید و بند کا شکار ہیں یا ان کی آزادی کسی
اور طرح سے سلب کی جاچکی ہے.ان لوگوں کی کسی بھی قسم کی خدمت جو اس نظریہ کی
روح کے منافی ہو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتی.اس لحاظ سے کم
ترقی یافتہ ممالک کی مالی مدد کا موجودہ نظام جس میں مدد کے ساتھ بہت سی شرائط اور
پابندیاں عائد کر دی جاتی ہیں کلیتہ مسترد کئے جانے کے لائق ہے.(۲) اس کے بعد اول حق یتیم کا ہے.یتیم کا کوئی سر پرست ہو یا نہ ہو ضروری
ہے کہ اس کے لئے مناسب خوراک کا بندو بست کیا جائے.(۳) اس کے بعد ایسے نادار اور مسکین کا حق ہے جو غربت کے ہاتھوں مٹی میں
مل چکا ہو.اس کے لئے بھی خور و نوش کا تسلی بخش انتظام کیا جانا ضروری ہے.اگر چہ ان آیات میں بظاہر خطاب تو صیغہ واحد میں ہے لیکن صاف ظاہر ہے کہ
یہاں ذکر ایک بہت بڑی اور وسیع تر مصیبت کا ہو رہا ہے.لفظ یوم کے معنی دن کے
ہیں.آیات کا مفہوم اور عمومی طرز بیان واضح طور پر بتا رہا ہے کہ امیر طاقتور اور
بڑے بڑے ممالک غریب کی نامساعد حالات میں مدد تو کرتے ہیں لیکن اس کے
ساتھ کئی قسم کی پابندیاں اور شرائط بھی عائد کر دیتے ہیں اس طرح مدد کی حقیقی روح
ختم ہو جاتی ہے اور اصل مقصد فوت ہو جاتا ہے.ایک دکھ سے بظاہر رہائی پاتے ہی
قوم ایک اور مصیبت کا شکار ہو جاتی ہے.ان آیات میں عالمی امداد کے اس موجودہ
248
Page 261
نظام کا مختصر اور دوٹوک الفاظ میں ذکر کر دیا گیا ہے.مومنوں سے کہا گیا ہے کہ غریب
اور بے کس افراد یا اقوام کے مصائب اور دکھوں کا ازالہ تو کریں مگر ان کی بے بسی
سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کی آزادی سلب نہ کریں یتیم کا لفظ وسیع تر معنوں
میں استعمال ہوا ہے اس کا اطلاق ان افراد یا قوموں پر بھی ہوتا ہے جن کا سارا
انحصار دوسروں کی مدد پر ہے.ایسی قوموں کی مثال ان یتیموں کی طرح ہے جن کے
امیر رشتہ داروں نے ان سے قطع تعلق کر لیا ہو.پس انہیں اس امید پر بے یارو مددگار
نہیں چھوڑ دینا چاہئے کہ شاید ان کے رشتہ دار جن پر ان کی امداد کی اصل
ذمہ داری عائد ہوتی ہے ان کی مدد کے لئے آگے آئیں.تیل کی دولت سے مالا مال
ممالک اس کی بہترین مثال ہیں.اگر صرف خلیج ہی کی چند ایک ریاستیں مل کر بنی نوع
انسان کے مصائب کو کم کرنے کی کوشش کرتیں تو وہ براعظم افریقہ میں بھوک اور قحط کا
مسئلہ حل کر سکتی تھیں جب کہ ان کے اپنے خزانوں میں اس سے ذرہ بھی کمی واقع نہ
ہوتی.بینکوں میں موجود دولت کے پہاڑوں سے انہیں جو سود ملتا ہے اور مغربی
ممالک میں موجود اثاثوں سے انہیں جو آمد ہوتی ہے سرزمین افریقہ کے دکھوں اور
مصائب کو کم کرنے کے لئے وہی کافی ہے.یوں بھی سود کی جو رقم یہ ممالک حاصل
کرتے ہیں اسے اپنے استعمال میں نہیں لا سکتے کیونکہ اسلام انہیں ایسا کرنے سے
روکتا ہے.اسی طرح بنگلہ دیش میں طرح طرح کی آفات کے نتیجہ میں پیدا ہونے
والے کروڑوں غریب اور بھوکے افراد بھی ہماری توجہ کے مستحق ہیں.اس قوم کو
ساری دنیا نے اس کے حال پر چھوڑ دیا ہے اور اگر کچھ امداد ان تک پہنچتی بھی ہے
تو وہ ان کے دکھوں کا مداوا کرنے کے لئے بالکل نا کافی ہے.یہ وہ قومیں ہیں جنہیں
یتیم سمجھا جانا چاہئے کیونکہ یتیم کا لفظ اپنے وسیع تر معنوں میں ان پر یقیناً اطلاق پاتا
ہے.اگر ایسی اقوام کو ان کے قریبی رشتہ دار بھی حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں تو
249
Page 262
اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہ کوتا ہی ایک سنگین جرم قرار پائے گی.غریب قوموں کے مصائب کے لئے اللہ تعالیٰ یا قدرت کو موردِ الزام نہیں ٹھہرایا
جاسکتا اس قسم کی سوچ نادانی اور کج فہمی پر مبنی ہو گی.دراصل انسان خود اس بے رحمی
اور بے حسی کا ذمہ دار ٹھہرتا ہے.اگر ہم انسانوں کے دلوں میں دوسروں کی خاطر دکھ
اٹھانے کا جذبہ بھر دیں تو آج بھی یہ دنیا جنت میں تبدیل ہو سکتی ہے.عالم اسلام سے باہر کی دنیا میں بھی ہر جگہ ایسی خود غرضی کارفرما دکھائی دیتی ہے.مثلاً اگر ایتھوپیا کے سوویت یونین کے ساتھ قریبی تعلقات ہیں تو اوروں کے لئے
اس کی مدد نہ کرنے کا یہ بہانہ نہیں ہونا چاہئے کہ یہ تمام تر سوویت یونین کی ذمہ داری
ہے.اگر مسلمان ملک سوڈان میں کروڑوں لوگ بھوکے مر رہے ہیں تو ان کی اس
قابل رحم حالت سے یہ کہہ کر آنکھیں بند نہیں کی جاسکتیں کہ ان کو کھلانے پلانے کی
ذمہ داری سعودی عرب پر عائد ہوتی ہے یا تیل کی دولت سے مالا مال دیگر مسلمان
ممالک پر ہے کیونکہ وہی سوڈان کے قریبی اور دوست ممالک ہیں.يَتِيمًا ذَاسَفْرَبَةِ
کے لفظی معنی ایسے یتیم کے ہیں جو نزد یکی رشتہ دار ہو.اس آیت میں یہ بھی اشارہ
کیا گیا ہے کہ مالی مشکلات میں مبتلا افراد یا قوموں کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے میں
مدد دینی چاہئے.تیسری دنیا کے اکثر ممالک میں ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ ان کی
معیشت بر وقت اور بڑے پیمانہ پر امداد نہ ملنے کی وجہ سے تیزی سے تباہی کا شکار ہو
رہی ہے.قرآن کریم کی اس آیت کے مطابق مدد کی تیسری ممکنہ صورت أَوْ مِسْكِينَا ذَا
مشربَةِ کا اطلاق ایسی معیشت پر ہوتا ہے جو بالکل تباہ ہو چکی ہو اور اقتصادی نظام
کی پوری عمارت ہی پیوند خاک ہو چکی ہو.قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق ایسے
ممالک کے لوگوں کا پیٹ بھر دینا ہی کافی نہیں ہے بنی نوع انسان کی یہ بھی ذمہ
250
Page 263
داری ہے کہ وہ ایسے اقدامات کریں جن کے ذریعہ ان ممالک کی معیشت کو بحال
کیا جا سکے.بدقسمتی سے موجودہ دور کے تجارتی تعلقات کی نوعیت اس کے بالکل
برعکس ہے.دولت کا بہاؤ امیر اور زیادہ ترقی یافتہ ممالک کی طرف ہے جبکہ غریب
ممالک کی اقتصادیات قرضوں کے بوجھ تلے دبی چلی جا رہی ہیں.میں ایک
ماہر اقتصادیات تو نہیں ہوں لیکن کم از کم اتنا ضرور سمجھتا ہوں کہ تیسری دنیا کے ممالک
کے لئے ترقی یافتہ ممالک کے ساتھ دو طرفہ تجارتی تعلقات کو جاری رکھنا اپنی دولت
کے ان ممالک کی طرف بہاؤ کو رو کے بغیر ناممکن ہے.اور ظاہر ہے کہ دولت کے اس
بہاؤ کو برآمدات سے حاصل ہونے والی آمد اور درآمدات پر اٹھنے والے خرچ کو
برابر اور یکساں کر کے ہی روکا جا سکتا ہے.ایک اور اہم بات بھی پیش نظر رہنی چاہئے کہ معاشی طور پر ترقی یافتہ اقوام میں
اپنا معیار زندگی بہتر بنانے کی ایک دائمی خواہش موجود ہے.غریب قوموں کی بھی
حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ بھی قرض لے کر اپنے معیار زندگی کو ترقی یافتہ دنیا کے
معیار کے مطابق بنا لیں حالانکہ وہ ٹیکنالوجی جس کے ذریعہ ہر کام بٹن دبانے سے
ہونے لگتا ہے ایک آسان اور آرام دہ زندگی کا عادی بنا دیتی ہے اور انسان میں
جفاکشی کی صفت کو نقصان پہنچاتی ہے.ترقی یافتہ ممالک کے بسنے والے سب لوگ اگر
محض اپنے پیٹ بھرنا چاہتے ہوں اور اپنے چہروں کو ہی صحت مند دیکھنا چاہتے ہوں تو
ان سے یہ توقع کیسے کی جاسکتی ہے کہ وہ غریب اقوام کو لاحق کمی خون کے جان لیوا
مرض کا کچھ مداوا کر سکیں گے.وہ ان نحیف و نزار قوموں کی خاطر کیا کر سکتے ہیں جبکہ
خود انکی اپنی خون کی پیاس نہیں سمجھ رہی.ہر وہ چیز جو خریدی جا سکتی ہے ان کی
معیشت کی طرف ہی منتقل ہو رہی ہے اور ان کا معیار زندگی ہر حال میں بلند تر ہوتا چلا
جا رہا ہے.معیار زندگی کو بلند سے بلند تر کرنے کی جو دیوانہ وار دوڑ ہر طرف لگی ہوئی
251
Page 264
ہے اس کے نتیجہ میں غریب اقوام میں زندگی کی آخری رمق بھی مٹتی جا رہی ہے.صرف یہی نہیں بلکہ خود ترقی یافتہ ممالک کے لوگوں کا ذہنی سکون بھی اٹھ رہا ہے اور وہ
قناعت کی دولت سے محروم ہو رہے ہیں.تمام معاشرہ مصنوعی طور پر پیدا کی ہوئی
ضروریات کی تکمیل کے لئے سرگرداں ہے.ہر
شخص هَلْ مِن مزید کی کیفیت میں
مبتلا ہے ہر کوئی دوسرے سے آگے نکلنا چاہتا ہے.یہی وہ صورت حال ہے جو بالآخر
قوموں کو جنگ کی طرف لے جاتی ہے اور یہی وہ رجحان ہے جس کو اسلام نے بڑی
سختی سے روکا ہے.اسلام ایک ایسے معاشرہ کی تصویر پیش کرتا ہے جس میں لوگ اپنے
وسائل کے اندر رہتے ہوئے زندگی گزارتے ہوں اور آنے والے کسی مشکل وقت
کے لئے کچھ بچا کر رکھتے ہوں اور یہ طرز زندگی صرف فرد یا خاندان تک محدود نہ ہو
بلکہ قومی سطح پر بھی اسے اختیار کیا گیا ہو.غریب ممالک کے لئے ایسی صورت حال میں بہت سے خطرات مضمر ہیں.جسکی
وجہ یہ ہے کہ جب نئی ابھرنے والی معیشت کی طرف سے مقابلہ کے نئے چیلنج پیدا
ہوتے ہیں تو ترقی یافتہ ممالک مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں اور ان کی معیشت کا پہیہ
رک جاتا ہے.نتیجہ ایسے ملک تیسری دنیا کے ملکوں یا دیگر غریب ممالک کے ساتھ
اپنے تعلقات میں اور بھی زیادہ بے حسی اور بے رحمی کا مظاہرہ کرنے لگتے ہیں اور ایسا
ہونا ناگزیر ہے کیونکہ ان ممالک کی حکومتوں نے اپنے عوام کا معیار زندگی اس حد تک
بہر حال قائم رکھنا ہے جس کے وہ عادی ہو چکے ہیں.بالآخر یہ صورت حال بد سے
بدتر ہوتی چلی جاتی ہے اور ایسے عوامل کو جنم دیتی ہے جو جنگوں پر منتج ہوتے ہیں اور
اسلام انسانیت کو جنگوں سے محفوظ رکھنا چاہتا ہے.252
Page 265
قومی اور بین الاقوامی سیاسی امن
اسلام کسی سیاسی نظام کو کلیۂ رڈ نہیں کرتا...بادشاہت
جمہوریت کیا ہے؟
جمہوریت کا اسلامی تصور......اسلامی جمہوریت کے دوستون...مشاورت.....اسلامی حکومت کیا ہے؟
ملائیت
کیا مذہب کا وفادار مملکت کا غدار ہوسکتا ہے؟
کیا صرف مذہب ہی کو قانون سازی کا حق حاصل ہے؟.....اسلام اور ریاست
بین الاقوامی تعلقات کی بنیاد کامل انصاف پر ہے...اقوام متحدہ کا کردار
253
Page 267
إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الآسنتِ إِلَى أَهْلِهَا ۖ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
b
b
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
سَمِيعًا بَصِيرًا
(سورۃ النساء آیت ۵۹)
ترجمہ:.یقیناً اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے
حقداروں کے سپرد کیا کرو اور جب تم لوگوں کے درمیان
حکومت کرو تو انصاف کے ساتھ حکومت کرو.یقیناً بہت ہی
عمدہ ہے جو اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے.یقیناً اللہ بہت سننے والا
( اور ) گہری نظر رکھنے والا ہے.255
Page 269
اس امر کا جائزہ لینا بے حد ضروری ہے کہ آج قومی اور بین الاقوامی سطح پر
سیاسی امن کی کیا صورت حال ہے.سب سے پہلے اس سوال کا جواب دریافت کرنا
ہوگا کہ انسان کے لئے کون سا سیاسی نظام سب سے بہتر ہے.اس کے لئے یہ جاننا
بھی ضروری ہوگا کہ کیا کسی قوم کی بے اطمینانی اور ان کے مصائب کا باعث ان کے
سیاسی نظام کی ناکامی اور اس میں پائے جانے والے نقائص ہیں یا اس کے پس منظر
میں کوئی اور عوامل کارفرما ہیں.پھر یہ کہ کیا نظام کی ناکامی کا ذمہ دار خود نظام ہے یا
اس نظام کو چلانے والے؟ اور کیا جمہوری عمل کے ذریعہ اقتدار پر قابض خود غرض،
لالچی اور بدعنوان سیاسی راہنما بہتر ہیں یا مثال کے طور پر ایک ایسا آمر جو نیک
اور شریف انسان ہو؟ نیز اسلام عالمی امن کو یقینی بنانے کے لئے دیگر شعبہ ہائے
زندگی کی طرح سیاست دانوں کو بھی ایک مکمل ضابطہ اخلاق پر کار بند رہنے کی نصیحت
کرتا ہے.اسلام کسی سیاسی نظام کو کلیۂ رد نہیں کرتا
سب سے پہلے یہ بتانا ضروری ہے کہ جہاں تک مختلف سیاسی نظاموں کا تعلق ہے
اسلام نہ تو کلیۂ کسی سیاسی نظام کو رد کرتا ہے اور نہ ہی کسی ایک نظام کو سب
اعلیٰ و افضل قرار دیتا ہے.بلا شبہ قرآن کریم جمہوری نظام کا بھی ذکر کرتا ہے جس میں
عوام اپنے حکمران خود منتخب کرتے ہیں لیکن جمہوریت ہی اسلام کا تجویز کردہ واحد
نظام حکومت نہیں، نہ ہی ایک عالمگیر مذہب کا یہ کام ہے کہ وہ دنیا بھر کے مختلف ممالک
اور مختلف معاشروں کے لئے ایک ہی قسم کا نظام حکومت تجویز کرے کیونکہ ایک ہی
سیاسی نظام مختلف علاقوں اور مختلف معاشروں کے لئے قابل عمل نہیں ہو سکتا.257
Page 270
دنیا کی ترقی یافتہ اقوام میں بھی جمہوری عمل اس اوج کمال تک نہیں پہنچا جس
سے ایک منظم معاشرہ تشکیل پاتا ہے جو جمہوریت کی آخری منزل ہے.حقیقت یہ ہے
کہ ایک طاقتور سرمایہ دارانہ نظام میں منظم قوموں اور حلقہ ہائے مفاد کی موجودگی میں
صحیح معنوں میں غیر جانبدارانہ انتخاب ہو ہی نہیں سکتے.اسی طرح بدعنوانی کا بڑھتا
ہوا سیلاب بھی حقیقی جمہوریت کے وجود کے لئے ایک خطرہ سے کم نہیں.اسی طرح
مافیا (Mafia) یعنی خفیہ تنظیموں اور دھونس، دھاندلی سے کام لینے والے دیگر گروہوں
کو دیکھتے ہوئے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے جمہوری ممالک میں بھی
جمہوریت محفوظ ہاتھوں میں نہیں ہے.سوال یہ ہے کہ پھر تیسری دنیا کے لئے
جمہوریت ایک بہترین نظام کیونکر ہو سکتا ہے.کیا افریقہ، جنوبی امریکہ اور ایشیا کے
ممالک میں مثالی جمہوریت کا نفاذ ایک کھوکھلا اور بے بنیاد دعویٰ تو نہیں ہے؟
میں سمجھتا ہوں کہ اسلام دنیا کے کسی سیاسی نظام کو کلیتہ رد نہیں کرتا اور اس امر کو
عوام کی صوابدید پر چھوڑتا ہے کہ وہ کون سا سیاسی نظام پسند کرتے ہیں اور اسے کس
حد تک اپنے تاریخی ورثہ اور روایات سے ہم آہنگ کر سکتے ہیں.دراصل اسلام
طرز حکومت اور اس کے ظاہری خدو خال پر زور نہیں دیتا بلکہ وہ اس امر پر زور دیتا
ہے کہ حکومت کو کس طرح اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی چاہئیں.مختلف طرز ہائے حکومت
مثلاً بادشاہت، فیوڈل سٹم وغیرہ سب کی اسلام میں گنجائش موجود ہے بشرطیکہ وہ
نظام حکومت عوام سے متعلق اپنی ذمہ داریوں کو اسلام کے دیئے ہوئے مثالی تصور
کے مطابق ادا کرے.بادشاہت
قرآن کریم نے بادشاہت کا بار بار ذکر کیا ہے اور کہیں بھی بطور ایک نظام کے
258
Page 271
اس کی مذمت نہیں کی.ایک اسرائیلی نبی کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کریم فرماتا ہے
کہ انہوں نے طالوت بادشاہ کے زیر نگیں بنی اسرائیل کو یاد دلاتے ہوئے کہا
ہے:
وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوْتَ مَلِكَاءَ قَالُوا أَنَّى يَكُوْنُ
و
لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ
قَالَ إِنَّ اللهَ اصْطَفَهُ عَلَيْكُمْ وَ زَادَهُ بَسْطَةَ فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ ، وَاللَّهُ
280
يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَالله وَاسِعٌ عَلِيم
(سورة البقرة آیت: ۲۴۸)
ترجمہ:.اور ان کے نبی نے ان سے کہا کہ یقیناً اللہ نے تمہارے لئے
طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے.انہوں نے کہا کہ اس کو ہم پر حکومت کا حق
کیسے ہوا جب کہ ہم اس کی نسبت حکومت کے زیادہ حقدار ہیں.اور وہ تو
مالی وسعت ( بھی ) نہیں دیا گیا.اس ( نبی ) نے کہا یقیناً اللہ نے اسے تم
پر ترجیح دی ہے اور اسے زیادہ کر دیا ہے علمی اور جسمانی فراخی کے لحاظ
سے.اور اللہ جسے چاہے اپنا ملک عطا کرتا ہے.اور اللہ وسعت عطا
کرنے والا (اور ) دائمی علم رکھنے والا ہے.ط
قرآن کریم نے حکومت کے وسیع تر معنوں میں عوام کی بادشاہت کا ذکر فرمایا
وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَقَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيْكُمْ أَنْبِيَاءَ
قي |
وَجَعَلَكُمْ مُلُوكَا وَّاتَكُمْ مَّالَمْ يُؤْتِ اَحَدًا مِّنَ الْعَلَمِينَ (سورة المائدة آيت ۲۱)
ترجمہ:.اور (یاد کرو) وہ وقت جب موسی نے اپنی قوم سے کہا
اے میری قوم! اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو جب اس نے تمہارے
درمیان انبیاء بنائے اور تمہیں بادشاہ بنایا اور اُس نے تمہیں وہ کچھ دیا جو
جہانوں میں سے کسی اور کو نہ دیا.259
Page 272
اسی طرح فتوحات کے ذریعہ نئی سلطنتوں کے قیام یا ان کی توسیع کو بالعموم اچھا
نہیں سمجھا گیا.اس بات کا ذکر ملکہ سبا سے متعلق قرآنی آیات میں ملتا ہے.ملکہ سبا
نے اپنے مشیروں کو نصیحت کرتے ہوئے جو بات کی اسے قرآن کریم نے یوں بیان
فرمایا ہے.قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوْهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةٌ
وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ
(سورۃ النمل آیت ۳۵)
ترجمہ:.اس نے کہا یقیناً جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اس
میں فساد برپا کر دیتے ہیں اور اس کے باشندوں میں سے معزز لوگوں کو
ذلیل کر دیتے ہیں اور وہ اسی طرح کیا کرتے ہیں.حقیقت یہ ہے کہ بادشاہ اچھے بھی ہو سکتے ہیں اور بُرے بھی بالکل اسطرح جیسے
جمہوری طریق پر منتخب کردہ وزیر یا صدر اچھے یا بُرے ہو سکتے ہیں لیکن قرآن کریم
نے بادشاہوں کی ایک ایسی قسم کا ذکر بھی کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ تھے مثلاً
حضرت سلیمان کا شمار ایسے ہی بادشاہوں میں ہوتا ہے.یہود اور نصاری تو
حضرت سلیمان کو ایک بادشاہ ہی سمجھتے ہیں لیکن قرآن کریم کے نزدیک وہ صرف
بادشاہ ہی نہیں اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ نبی بھی تھے.اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ
کبھی اللہ تعالیٰ ایک ہی شخص کو بیک وقت نبوت اور بادشاہت کے منصب پر سرفراز فرما
دیتا ہے.ایسے لوگ براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ہوتے ہیں.نبوت
کے ذریعہ حاصل ہونے والی حکومت کی ایک اور قسم کا ذکر بھی قرآن کریم میں ہمیں
ملتا ہے.مندرجہ ذیل آیت اس کی وضاحت کرتی ہے.يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُوْلَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ
تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
260
Page 273
الأخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاه
(سورۃ النساء آیت ۶۰)
ترجمہ :.اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو! اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی
اطاعت کرو اور اپنے حکام کی بھی.اور اگر تم کسی معاملہ میں (اولوالامر
سے ) اختلاف کرو تو ایسے معاملے اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دیا کرو
اگر (فی الحقیقت) تم اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان لانے والے ہو.یہ
بہت بہتر ( طریق) ہے اور انجام کے لحاظ سے بہت اچھا ہے.اس آیت کریمہ میں حاکمیت اعلیٰ کی بعض اور اقسام کا ذکر ہے نیز اس آیت
میں زور اس امر پر دیا گیا ہے کہ ضروری نہیں کہ جمہوری طرز پر کیا گیا انتخاب درست
بھی ہو عین ممکن ہے کہ عوام کی غالب اکثریت کسی لیڈر کی عظیم قائدانہ صلاحیتوں کو
پہچاننے سے قاصر رہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ اگر ایک ایسے عظیم لیڈر کو ان پر بطور حاکم
مقرر کر دیا جائے تو عوام اس کے خلاف سراپا احتجاج بن جائیں.کسی بھی سیاسی پیمانہ
سے اسے ماپا جائے تو ایسے حکام کا تقرر آمرانہ متصور ہوگا.اب یہ فیصلہ عوام کی مرضی
کے خلاف ہو تو ہو، ان کے حقیقی مفاد کے خلاف ہرگز نہیں ہوگا.جمہوری طرز کے انتخاب میں بنیادی طور پر یہ نقص ہے کہ لوگ محض اپنے سطحی اور
وقتی تاثر کی بناء پر جذبات میں آکر عجلت میں فیصلہ کرتے ہیں.وہ اس بات کے اہل
نہیں ہوتے کہ اپنے لئے ان بہترین لوگوں کو منتخب کر سکیں جو قیادت کی اعلیٰ صفات
سے متصف ہوں اور ان کے حقیقی مفاد کی حفاظت کر سکیں.اللہ تعالیٰ کے قائم کردہ سلسلوں کی تاریخ کو دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ الہی
جماعتوں پر ایسے نازک وقت بھی آتے رہے ہیں جب ان کی سیاسی بقا بظاہر
معرض خطر میں تھی تب اللہ تعالیٰ نے بادشاہ حاکم یا لیڈر کے انتخاب کا کام خود اپنے
ہاتھ میں لے لیا.لیکن اس سے یہ نتیجہ نہیں نکالنا چاہئے کہ سب بادشاہ یا قائدین
261
Page 274
اللہ تعالیٰ کے منتخب کردہ ہوتے ہیں یا کسی قسم کے تقدس کے حامل ہوتے ہیں.یہ غلط
تصور قرون وسطی میں عیسائیت کے قائم کردہ نظام میں عام ہو چکا تھا مگر قرآن کریم
ہرگز اس کی تائید نہیں کرتا مثلا رچرڈ بادشاہ یہ نوحہ کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ:
Not all the waters of rough rude seas can wash the balm
of an annointed king.(Shakespeare)
یعنی سارے سمندروں کا کھارا پانی بھی اس مرہم کو نہیں دھو سکتا جو مقدس بادشاہ
کے ہاتھ کا لگایا ہوا ہے (شیکسپیر)
جمہوریت کیا ہے؟
جمہوریت کا تصور اگرچہ یونانی ہے لیکن ابراہیم لنکن نے جمہوریت کی جو
مندرجہ ذیل مختصر تعریف کی ہے وہی اس کی بنیاد ہے
Government of the people, by the people,
for the people.یعنی جمہوریت نام ہے اس حکومت کا جو عوام کی حکومت ہو عوام کے ذریعہ ہو
اور عوام کے لئے ہو.ہے تو یہ ایک گھسا پٹا مقولہ لیکن ہے دلچسپ جو شاید ہی کبھی دنیا
میں کسی حکومت پر صادق آیا ہو.اس تعریف کا آخری حصہ یعنی ” عوام کے لئے
حکومت ایک بالکل مبہم سی بات ہے اور اس میں کئی قسم کے خطرات پوشیدہ ہیں.کیا
کسی حکومت کے متعلق ہم وثوق سے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ عوام کے لئے ہے؟
اقتدار اکثریت کے پاس ہو تو عوام سے مراد صرف اکثریت ہے نہ کہ اقلیت.جمہوری طرز حکومت میں اہم نوعیت کے فیصلے محض اکثریت کے بل بوتے پر کر لئے
جاتے ہیں.لیکن اگر تمام حقائق اور اعداد و شمار کا بغور جائزہ لیا جائے اور ان کا
تجزیہ کیا جائے تو معلوم ہو گا کہ در حقیقت یہ تو جمہوری طرز پر منتخب کردہ ایک اقلیت
262
Page 275
کا فیصلہ تھا جو اکثریت پر مسلط کر دیا گیا.ایک ممکنہ صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ
حکمران پارٹی کچھ انتخابی حلقوں میں دوسری پارٹیوں کی نسبت معمولی اکثریت
حاصل کر کے اقتدار میں آ جائے جبکہ دراصل اسے حقیقی اکثریت حاصل نہ ہو.اسی
طرح اگر انتخابات میں ڈالے گئے ووٹوں کا تناسب کم رہے تو بھی یہ بات مشکوک
ہو جاتی ہے کہ حکمران پارٹی کو واقعی اکثریت کی حمایت حاصل ہے.پھر ایک
سیاسی جماعت اگر مجموعی طور پر باقی جماعتوں سے زیادہ ووٹ حاصل کر بھی لیتی
ہے تب بھی اس کے اقتدار کے دوران کئی ایسے واقعات رونما ہو سکتے ہیں جن سے
صورت حال یکسر بدل جائے.مثلاً رائے عامہ کلیہ تبدیل ہو سکتی ہے جس کے نتیجہ
میں حکمران جماعت اکثریت کی حقیقی نمائندہ ہی نہیں رہتی.عوام میں بتدریج ہونے
والی ذہنی تبدیلی بالآخر حکومت کی تبدیلی کے وقت صاف نظر آنے لگتی ہے.اگر
عوام میں حکومت کی مقبولیت برقرار بھی رہے تب بھی یہ کوئی بعید از قیاس بات نہیں
ہے کہ اہم فیصلے کرتے ہوئے حکمران پارٹی کے ساتھ اپنی وفاداری نبھانے کی
خاطر اس فیصلہ کے حق میں اپنا ووٹ دیا ہو.اب اگر مخالف جماعتوں کے بالمقابل
حکمران جماعت کے اپنے اراکین میں اختلاف پایا جاتا ہے تو بسا اوقات ایسا ہوگا
کہ اکثریتی جماعت کا فیصلہ در حقیقت ایک اقلیت کا فیصلہ ہو گا جسے عوام پر ٹھونسا
جائے گا.یہ بات بھی قابل غور ہے کہ عوام کے مفاد کا تصور اور اچھے اور برے کا تصور وقت
کے ساتھ ساتھ بدلتا بھی رہتا ہے اس لئے اگر فیصلے ابدی اور دائمی اصولوں کی بنیاد پر نہ
کئے جائیں بلکہ فرد واحد کی صوابدید یا ایک پارٹی کی پسند نا پسند کی روشنی میں عوامی بہبود
کے فیصلے ہوں تو اس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ پالیسی ہمیشہ تبدیل ہوتی رہے گی.جو کچھ آج
اچھا دکھائی دے رہا ہے ہوسکتا ہے کہ کل کو برا نظر آنے لگے اور جو کل برا ہے وہ پرسوں
263
Page 276
اچھا بن جائے اور یہ صورت حال ایک عام آدمی کو مخمصہ میں مبتلا کر سکتی ہے.کمیونزم کا
نصف صدی سے زائد عرصہ تک جاری رہنے والا وسیع تجربہ آخر اسی نعرہ پر ہی تو مبنی تھا
کہ یہ سب کچھ عوام کے لئے ہے.آخر تمام سوشلسٹ ریاستوں میں آمرانہ نظام ہی تو
رائج نہیں تھا.اسی طرح جمہوری طرز حکومت میں جہاں تک عوام کے ذریعہ حکومت کا
سوال ہے تو اس لحاظ سے بھی سوشلسٹ ممالک اور جمہوری ممالک میں فرق یا تو بہت کم
ہے یا سرے سے موجود ہی نہیں ہے.ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ سوشلسٹ ممالک
میں منتخب ہونے والی تمام کی تمام حکومتیں عوام کے ذریعہ قائم نہیں ہوئیں اس لئے قابل
مذمت ہیں ہاں البتہ آمرانہ نظام حکومت والے ممالک میں عین ممکن ہے کہ حکومت اپنی
پسند کے امیدواروں کو منتخب کرانے کے لئے عوام کو اس رنگ میں مجبور کر دے کہ ان
کے پاس کوئی اور راستہ اختیار کرنے کی گنجائش ہی نہ رہے.مغربی دنیا کے چند ایک
ممالک کو چھوڑ کر باقی دنیا کے جمہوری ممالک میں بھی ایسے ہتھکنڈوں کا استعمال ہرگز
بعید از قیاس نہیں ہے.حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں اکثر جگہ جمہوریت کو پوری آزادی حاصل نہیں ہے.بہت کم ایسے انتخابات منعقد ہوتے ہیں جن کے بارہ میں کہا جا سکے کہ صحیح معنوں میں
عوام کے ذریعہ ہوئے ہیں.دھاندلیوں، ہارس ٹریڈنگ اور پولیس وغیرہ کے ذریعہ
خوف و ہراس پھیلانے اور ایسے ہی دیگر نا جائز ہتھکنڈوں کے استعمال سے جمہوریت
کی روح اتنی کمزور پڑ چکی ہے کہ اب جمہوریت کا صرف نام باقی رہ گیا ہے.جمہوریت کا اسلامی تصور
قرآن کریم کے مطابق لوگ اپنے لئے کوئی سا بھی نظام حکومت جو ان کے
مناسب حال ہو اختیار کرنے میں آزاد ہیں.جمہوریت، بادشاہت، قبائلی نظام،
264
Page 277
جاگیردارانہ نظام کبھی درست اور بجا ہیں بشرطیکہ ایسا نظام ایک اچھی روایت اور ورثہ
کے طور پر عوام کو بھی قابل قبول ہوتا ہم معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم نے جمہوریت کو
باقی سب نظاموں پر ترجیح دی ہے اور مسلمانوں کو جمہوری نظام اپنانے کی تلقین کی
ہے اگر چہ قرآن کریم میں جمہوریت کا تصور وہ نہیں ہے جو مغربی طرز جمہوریت میں
ہمیں دکھائی دیتا ہے.قرآن کریم نے کہیں بھی جمہوریت کی کھوکھلی اور سطحی تعریف
پیش نہیں کی.قرآن کریم صرف غایت درجہ کے اہم اور بنیادی اصول بیان فرماتا
ہے اور باقی تفاصیل خود عوام کی مرضی پر چھوڑ دیتا ہے.اب اگر کوئی قرآن کریم کی تعلیم
پر
عمل کرے گا تو وہ فائدہ اٹھائے گا اور اگر وہ صحیح راستہ کو چھوڑے گا تو ہلاک ہوگا.اسلامی جمہوریت کے دو ستون
جمہوریت کے اسلامی تصور کے دو بنیادی ستون ہیں.۱- انتخابات کا جمہوری عمل کلیۂ دیانت داری پر مبنی ہونا چاہئے.اسلام ہمیں یہ تعلیم
دیتا ہے کہ ووٹ کا حق استعمال کرتے وقت ہمیشہ یہ احساس رہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ
رہا ہے.پس جہاں ہم اپنے فیصلہ کے ذمہ دار ہیں وہاں اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی
جوابدہ ہیں اس لئے ووٹ اس کو دیا جائے گا جو اس قومی ذمہ داری کو ادا کرنے کا
نہ صرف سب سے زیادہ اہل ہو بلکہ خود بھی دیانت دار ہو.اس تعلیم میں یہ بات بھی
مضمر ہے کہ ووٹ ڈالنے کا حق رکھنے والے سب لوگ اپنے اس حق کو ضرور استعمال
کریں سوائے اس کے کہ وہ حالات کے آگے بے بس ہوں یا اس حق کے استعمال میں
کوئی اور رکاوٹ حائل ہو.۲.حکومتوں کو کامل انصاف کے اصول پر کام کرنا چاہئے.اسلامی جمہوریت کا
دوسرا ستون یہ ہے کہ فیصلے کرتے ہوئے کامل انصاف کو اپنا یا جائے.انصاف سے
265
Page 278
کسی قیمت پر بھی انحراف نہ کیا جائے خواہ معاملہ سیاسی ہو یا سماجی یا اقتصادی.حکومت
کی تشکیل کے بعد پارٹی کے اندر ہونے والی ووٹنگ کے دوران ہمیشہ انصاف کے
تقاضوں کو پورا کیا جائے.پارٹی کا کوئی مفاد یا کوئی سیاسی مصلحت ان فیصلوں پر اثر
انداز نہیں ہونی چاہئے.اپنے دور رس نتائج کے لحاظ سے اس روح کے ساتھ کئے گئے
فیصلوں پر ہی جمہوریت کی وہ تعریف صادق آئے گی جو ابراہیم لنکن نے پیش کی تھی.یعنی ایسی حکومت عوام کی حکومت ہوگی، عوام کے ذریعہ ہوگی اور عوام کے لئے ہوگی.مشاورت
قرآن کریم نے جمہوریت کی روح اور اس کے مرکزی نکتہ کو بڑی وضاحت کے
ساتھ بیان فرمایا ہے اور مسلمانوں کو بتایا ہے کہ بلاشبہ جمہوریت باقی تمام نظاموں
سے بہتر نظام حکومت ہے تاہم بادشاہت کو کہیں بھی لا دین اور مذموم طرز حکومت قرار
دے کر کلیۂ رد نہیں کیا گیا ہے.قرآن کریم ایک مثالی اسلامی معاشرہ کا ذکر کرتے
ہوئے فرماتا ہے.فَمَا اوتيتم مِن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا، وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ
°
ده
10w 28 0.امَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبِيرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا
مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَ أَقَامُوا الصَّلوةَ ، وَأَمْرُهُمْ
وه
-- وه
وہ
٥٠٠ و ہ وہ وہ
0-06 60
شورى بينهم ص و مما رزقنهم ينفقون 0 والذين إذا أصابهم البغى هم
( سورة الشوریٰ آیات ۳۷ تا ۴۰)
يَنتَصِرُونَ
ترجمہ :.پس جو بھی تمہیں دیا گیا ہے وہ دنیا کی زندگی کا عارضی سامان
ہے اور جو اللہ کے پاس ہے وہ اچھا اور ان لوگوں کے لئے سب سے
زیادہ باقی رہنے والا ہے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر توکل کرتے
266
Page 279
ہیں اور جو بڑے گنا ہوں اور بے حیائی کی باتوں سے اجتناب کرتے ہیں
اور جب غضبناک ہوں تو بخشش سے کام لیتے ہیں اور جو اپنے رب کی
آواز پر لبیک کہتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور ان کا امر باہمی مشورہ
سے طے ہوتا ہے اور اس میں سے جو ہم نے انہیں عطا کیا خرچ کرتے
ہیں.اور وہ جن پر جب زیادتی ہوتی ہے تو وہ بدلہ لیتے ہیں.أَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ کا تعلق مسلم معاشرہ کی سیاسی زندگی سے ہے.اس کا
صاف مطلب یہ ہے کہ امور سلطنت سے متعلق ان کے فیصلے باہمی مشاورت سے طے
پاتے ہیں.جمہوریت کی مندرجہ بالا تعریف کا پہلا حصہ یعنی حکومت عوام کی ہے اسی
آیت مبارکہ کی تصدیق کر رہا ہے.چنانچہ ایک مسلم معاشرہ میں عوامی رائے باہمی
مشورہ کے طفیل حکومتی فیصلہ بن جاتی ہے.جمہوریت کی تعریف کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ حکومت لوگوں کے ذریعہ ہو.یہ امر
بڑی وضاحت سے مندرجہ ذیل آیت میں بیان کیا گیا ہے."
إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا إِلَّا سُنتِ إِلَى أَهْلِهَا (سورۃ النساء آیت ۵۹)
ترجمہ:.یقینا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے حقداروں کے
سپرد کیا کرو.اس کا معنی یہ ہے کہ جب بھی حکومت کا انتخاب کرو تو ہمیشہ امانت ان لوگوں کے
سپرد کرو جو اس کے سب سے زیادہ اہل ہوں.یہاں انتخاب کے اس عوامی حق کا
مفہوماً ذکر کیا گیا ہے.اصل میں قرآن کریم زور اس بات پر دیتا ہے کہ اس حق کا استعمال کس طرح کیا
جانا چاہئے.مسلمانوں کو یاد دلایا گیا ہے کہ یہ صرف ان کی ذاتی پسند یا نا پسند کا سوال
نہیں ہے بلکہ اس سے بڑھ کر انتخاب کا حق ایک قومی امانت ہے اور جہاں امانت کا
سوال ہو وہاں انسان اتنا آزاد نہیں ہوتا کہ جو چاہے کرتا پھرے بلکہ لازم ہے کہ وہ
267
Page 280
امانت کا حق پوری سچائی، ایمانداری اور ذاتی اغراض سے بالاتر ہو کر ادا کرے
اور امانت ایسے لوگوں کے سپرد کی جائے جو درحقیقت اس کے اہل ہوں.بہت سے مسلمان علماء کے نزدیک اس آیت میں یہ اشارہ کیا گیا ہے کہ اسلام کا
جمہوریت کے متعلق وہی نظریہ ہے جو مغرب کا سیاسی فلسفہ پیش کرتا ہے جبکہ حقیقت یہ
ہے کہ یہ بات محض جزوی طور پر ہی درست ہے.قرآن کریم نے شوری کے جس
نظام کا ذکر کیا ہے اس میں عصر حاضر کی مغربی جمہوریتوں اور ان کی جماعتی
ریشہ دوانیوں کے لئے کوئی گنجائش باقی نہیں رکھی گئی.اسی طرح قرآن کریم اس طرز کے سیاسی بحث و مباحثہ کی اجازت بھی نہیں دیتا
جو آج کل کی جمہوری طور پر منتخب اسمبلیوں اور ایوان ہائے نمائندگان کا خاصہ ہے.اس موضوع پر چونکہ مفصل بحث پہلے گزر چکی ہے اس لئے یہاں اسے دوہرانے کی
ضرورت نہیں ہے.جمہوریت کی تعریف کے دوسرے حصہ Government by the people
کے ضمن میں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ باہمی مشورہ کے اس نظریہ کے مطابق ووٹ
دینے والے کو ووٹ کا حق مکمل اور غیر مشروط طور پر حاصل ہوتا ہے اور اس حق کو اس
سے چھینا نہیں جاسکتا.آجکل جو جمہوریت رائج ہے اس کے مطابق ایک ووٹر اگر چاہے تو اپنا ووٹ کسی
بے جان پتلے کو دیدے اور چاہے تو اسے بیلٹ بکس میں ڈالنے کی بجائے رڈی کی
ٹوکری میں پھینک دے.ہر دو صورتوں میں اسے کوئی ملامت نہیں کی جا سکتی نہ ہی
اسے جمہوریت کے کسی اصول کی خلاف ورزی پر کسی قسم کی تنقید کا نشانہ بنایا جا سکتا
ہے.لیکن یادر ہے کہ قرآن کریم جس جمہوریت کو پیش کرتا ہے اس کے مطابق ایک
رائے دہند اپنے اس حق کے استعمال میں مطلقاً آزاد نہیں ہے بلکہ ووٹ اس کے
268
Page 281
پاس ایک امانت ہے اور ایک امین کی حیثیت سے اسے چاہئے کہ وہ یہ امانت پورے
انصاف کے ساتھ واپس لوٹائے یعنی اپنا ووٹ اس شخص کو دے جو اس کا سب سے
زیادہ اہل ہے.ووٹ دینے والے کو اس بات سے خوب اچھی طرح آگاہ ہونا چاہئے کہ وہ ایک
دن اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے اعمال کا جوابدہ ہو گا.اس اسلامی تصور کے مطابق اگر
کسی سیاسی پارٹی کارکن اپنی ہی پارٹی کے نامزد امیدوار کے متعلق یہ سمجھتا ہے کہ وہ
اس قومی ذمہ داری کا اہل ثابت نہیں ہوگا تو اسے چاہئے کہ ایسے شخص کے حق میں
ووٹ دینے کی بجائے ایسی پارٹی سے الگ ہو جائے.پارٹی کے ساتھ وفاداری
حق رائے دہی کے آزادانہ استعمال میں روک نہیں بننی چاہئے.یہ بھی ضروری ہے کہ ہر ووٹر الیکشن کے دوران اپنا ووٹ ضرور استعمال کرے
سوائے اس کے کہ وہ بامر مجبوری ایسا کرنے سے قاصر ہو.اگر ووٹر اپنا ووٹ استعمال
نہیں کرتا تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ امانت کا حق ادا کرنے میں ناکام رہا ہے.بتایا جاتا ہے کہ امریکہ میں قریباً آدھے ووٹر اپنا ووٹ استعمال کرنے کی زحمت
ہی گوارا نہیں کرتے.اسلام کے نظریہ جمہوریت میں اپنے ووٹ کے عدم استعمال کی
کوئی گنجائش نہیں ہے.اسلامی حکومت کیا ہے؟
آج کے مسلمان سیاسی مفکرین کو یہ دعوی کرنے کا بڑا شوق ہے کہ اسلام
جمہوریت کا دوسرا نام ہے.ان کے سیاسی فلسفہ کے مطابق آخری اختیار چونکہ
اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اس لئے حاکمیت اعلیٰ بھی اسی کو حاصل ہے.قرآن کریم
269
Page 282
اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے:
فَتَعَلَى اللهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ، لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ
(سورۃ المومنون آیت ۱۱۷)
ترجمہ:.پس بہت بلند مرتبہ ہے اللہ سچا بادشاہ.اس کے سوا اور کوئی معبود
نہیں.معز ز عرش کا رب ہے.یہ بنیادی اصول کہ آخری اور حقیقی اقتدار کا مالک اللہ تعالیٰ ہے اور وہی سب
بادشاہوں کا بادشاہ ہے قرآن کریم میں کئی طرح سے بیان ہوا ہے جس کی ایک مثال
مذکورہ بالا آیت ہے.امور مملکت کی انجام دہی میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ کا اظہار دو طرح سے ہوتا
ہے.صلى الله
(الف) قانون شریعت جس کا ماخذ کلام الہی ہے.سنت رسول اللہ ﷺ اور
مستند احادیث جو قرون اولیٰ کے مسلمانوں نے رسول
اللہ ﷺ کے حوالہ سے بیان
کیں.یہ تین ذرائع اپنے مرتبہ کے لحاظ سے اول درجہ پر ہیں اور ہر قسم کی
قانون سازی کے لئے ضروری راہنمائی مہیا کرتے ہیں.کسی بھی جمہوری حکومت کو
یہ حق حاصل نہیں کہ وہ قرآن کریم، سنت رسول اللہ ﷺ اور احادیث مبارکہ میں
مذکور احکام الہی میں کسی قسم کی مداخلت کرے.(ب) کوئی ایسی قانون سازی جائز نہیں ہوگی جو مذکورہ بالا اصول سے ٹکراتی ہو.بد قسمتی یہ ہے کہ مختلف اسلامی فرقے اس بات پر متفق نہیں ہو سکے کہ شریعت کے واضح
اور دوٹوک قوانین کیا ہیں البتہ سب علماء اس پر متفق ہیں کہ قانون عطا کرنے کا حق
صرف اللہ تعالیٰ ہی کو حاصل ہے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آنحضرت ﷺ
قرآنی وحی کے ذریعہ اپنے آخری فیصلہ کا اظہار فرما دیا ہے.پر
270
Page 283
اب سوال یہ ہے کہ ایک مسلم مملکت کا نظم ونسق کس طریق پر چلایا جانا چاہئے.اس کے متعلق عام طور پر یہ خیال پایا جاتا ہے کہ روز مرہ کے انتظامی امور میں حکومت
عوام کے نمائندہ کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے اظہار کا ایک ذریعہ بن جاتی
ہے اور چونکہ حاکمیت ان معنوں میں عوام کی ہوتی ہے اور وہ اپنا اختیار انتخاب کے
ذریعہ نمائندوں کو منتقل کر دیتے ہیں اس لئے ایسا نظام جمہوری ہے.ملائیت
نام نہا د ملا عام مسلمانوں کے جدید جمہوری رجحانات سے صرف اس شرط پر متفق
ہو سکتے ہیں کہ جمہوری فیصلوں کو شریعت کی بنیاد پر قبول یا رد کرنے کا آخری اختیار
انہیں حاصل ہو.اس مطالبہ کو تسلیم کرنے کا بالفاظ دیگر مطلب یہ ہے کہ قانون سازی
کا آخری اختیار اللہ تعالیٰ کو نہیں بلکہ ملاؤں اور ان کے ساتھیوں کے ہاتھ میں دے
دیا جائے.ایسا زبر دست اختیار جب ان مولویوں کو مل جائے گا جن میں ابھی تک
اس بنیادی امر پر بھی اتفاق رائے نہیں کہ شریعت کیا ہے اور کیا نہیں تو ظاہر ہے کہ
اس کے بڑے خوفناک نتائج نکلیں گے.اتنے بے شمار فقہی مسالک ہیں کہ کسی ایک
مکتبہ فکر کے علماء بھی تمام شرعی احکامات پر متفق نہیں ہیں.مختلف شرعی احکامات میں
اللہ تعالیٰ کی اصل منشا کیا ہے اس پر بھی مختلف ادوار میں علماء کا موقف تبدیل ہوتا رہا
ہے.اس اعتبار سے آج عالم اسلام کو بڑے پیچیدہ مسائل کا سامنا ہے اور یہ کہنا غلط
نہیں ہوگا کہ اسلامی دنیا ابھی تک اپنی حقیقی شناخت کی تلاش میں ہے.مسلمان دانشوروں پر یہ حقیقت روز بروز آشکار ہوتی چلی جا رہی ہے کہ اگر
مولوی کسی ایک مطالبہ پر اکٹھے ہو سکتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ کسی قسم کی نرمی اور رعایت
کے بغیر جبراً شریعت کو نافذ کر دیا جائے.انقلاب ایران نے ان ممالک میں بھی
271
Page 284
ملاؤں کی اس آتش شوق کو مزید بھڑکا دیا ہے جہاں سنی مسلمانوں کی اکثریت ہے.وہ کہتے ہیں کہ اگر شیعہ رہنما جناب ثمینی انقلاب بر پا کر سکتے ہیں تو ہم کیوں کامیاب
نہیں ہوں گے.لیکن ملاں یہ نہیں جانتا کہ انقلاب کیا رنگ لائے گا اور اس کے کیا
نتائج ہوں گے.وہ تو صرف اپنی جنت الحمقاء میں بس رہا ہے.دوسری طرف عوام
ہیں جو عجیب مخمصوں میں پڑے ہوئے ہیں.انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اللہ تعالیٰ اور
رسول اللہ ﷺ کے احکامات کو مانیں یا اپنے سیاسی معاملات کو خوف خدا سے عاری
راہنماؤں کے سپرد کر دیں.ایک عام آدمی کے لئے اس سوال کا جواب تلاش کرنا
بے حد مشکل ہے.وہ حیران و پریشان ہے کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے.اکثر مسلمان
ممالک کے عوام اسلام سے شدید محبت رکھتے ہیں.ان کی محبت کا یہ عالم ہے کہ
اللہ تعالیٰ کی رضا اور ہمارے آقا و مولیٰ حضرت محمد مصطفی ﷺ کی ناموس کی خاطر
جان تک قربان کرنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں.بایں ہمہ ان حالات میں عام
آدمی طرح طرح کی ذہنی الجھنوں میں مبتلا ہے اور بے چینی کا شکار ہے.اللہ تعالیٰ
صلى الله
اور رسول اللہ ﷺ سے محبت کے باوجود لوگوں کو ماضی کے وہ خونیں ادوار بھی رہ
رہ کر یاد آتے ہیں جب یا تو حکومتیں مولویوں کی گرفت میں تھیں یا مولویوں کو حکومتیں
اپنا آلہ کار بنا کر سیاسی مفاد حاصل کر رہی تھیں.مسلمان سیاست دان بھی گومگو کی ایک کیفیت میں مبتلا ہیں اور بھانت بھانت کی
بولیاں بول رہے ہیں.ان میں سے بعض کو تو ملاں کی حمایت اور سر پرستی کئے بغیر
کھانا ہضم نہیں ہوتا.ان کی خواہش دراصل یہ ہوتی ہے کہ انتخابات میں لوگ انہیں
ملاں کی بجائے مجاہد اسلام کے طور پر منتخب کریں اور ملاں سے زیادہ انہیں شریعت کا
سر پرست اور محافظ سمجھیں.ان کے زعم میں اس
ہیں.ان کے زعم میں اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ زندگی نسبتاً
سہولت سے بسر ہوگی کیونکہ سارے معاملات کلیہ ان کے اپنے ہاتھوں میں رہیں گے
272
Page 285
جبکہ اگر جنت کے ٹھیکیداروں کو موقع مل گیا تو وہ کسی قسم کی کوئی نرمی اور رعایت روا
نہیں رکھیں گے.کچھ دور اندیش اور محتاط سیاست دان خوب سمجھتے ہیں کہ یہ ایک
خطر ناک کھیل ہے مگر افسوس کہ ایسے سیاست دانوں کی تعداد روز بروز گھٹ رہی
ہے.لگتا ہے کہ سیاست اور منافقت ایک طرف اور سچ اور دیانت دوسری طرف
کھڑے ہیں اور ان کا ایک دوسرے سے دور کا بھی واسطہ نہیں.بالعموم اہل دانش
روز بروز جمہوریت کی طرف مائل ہو رہے ہیں.یہ لوگ اسلام سے محبت تو رکھتے ہیں
لیکن ملاں کی حکومت سے خائف ہیں.وہ ہرگز جمہوریت کو اسلام کا بدل نہیں سمجھتے
بلکہ در حقیقت یہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ قرآن ہی ہے جس نے جمہوریت کو ایک سیاسی
فلسفہ کے طور پر پیش کیا ہے.چنانچہ فرمایا:
وہ
-- ووه
ه وه
وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلوةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ - وَمِمَّا
اوہ وہ وہ
رزقنهم ينفقون
(سورۃ الشوریٰ آیت (۳۹)
ترجمہ.اور جو اپنے رب کی آواز پر لبیک کہتے ہیں اور نماز قائم کرتے
ہیں اور ان کا امر باہمی مشورہ سے طے ہوتا ہے اور اس میں سے جو ہم
نے انہیں عطا کیا خرچ کرتے ہیں.وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ ، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
المتوكلين
ط
(سوۃ آل عمران آیت (۱۶۰)
ترجمہ:.اور (ہر) اہم معاملہ میں ان سے مشورہ کر.پس جب تو
(کوئی) فیصلہ کر لے تو پھر اللہ ہی پر توکل کر.یقینا اللہ تو کل کرنے
والوں سے محبت رکھتا ہے.مختلف گروہوں کے مابین اس رسہ کشی کا حاصل یہ ہے کہ پاکستان جیسے نئے
وجود میں آنے والے مسلمان ملک طرح طرح کی پیچیدگیوں اور تضادات کا شکار
273
Page 286
ہو جاتے ہیں.رائے دہندگان ہرگز یہ پسند نہیں کرتے کہ اسمبلیوں میں مولوی ہی
مولوی نظر آئیں.نفاذ شریعت کی تحریک زوروں پر ہو تو بھی بمشکل پانچ سے دس
فیصد مولوی انتخابات میں کامیاب ہوتے ہیں لیکن ملاں کی حمایت حاصل کرنے
کے شوق میں نفاذ شریعت کا وعدہ کر کے سیاست دان ایک مصیبت میں پھنس گئے
ہیں.وہ خوب سمجھتے ہیں کہ قانون ساز اسمبلیوں کے ذریعہ شریعت کا نفاذ اجتماع
نقیضین کے مترادف ہے.اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ قانون سازی کا حق صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے (جس
سے ایک مسلمان انکار نہیں کر سکتا ) تو اس کا منطقی نتیجہ یہ ہوگا کہ قانون کی تعریف اور
تفہیم کا حق صرف مولویوں اور فرقہ پرست علماء کو حاصل ہو جائے گا.اس صورتحال
میں قانون ساز اداروں کا سارا عمل یکسر بے معنی اور بے مصرف ہو کر رہ جائے گا.آخر اراکین پارلیمنٹ کا کام صرف یہ تو نہیں کہ جہاں ملاں انگلی رکھے آنکھیں بند کر
کے دستخط کر دیا کریں.المیہ یہ ہے کہ نہ تو سیاست دانوں نے اور نہ ہی دانشمندوں
نے کبھی سنجیدگی سے یہ سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ قرآن کریم حقیقتا کس طرز یا
طرز ہائے حکومت کو پیش فرماتا ہے یا تسلیم کرتا ہے.کیا مذہب کا وفادار مملکت کا غدار ہوسکتا ہے؟
اللہ تعالیٰ کے قول (یعنی مذہب) اور اس کے فعل ( یعنی فطرت ) میں ہرگز کوئی
تضاد نہیں ہو سکتا.یہ ممکن ہی نہیں کہ فطرت انسانی میں تو وطن کی محبت کا جذبہ پایا
جائے مگر مذہب اس کے خلاف تعلیم دے اسلامی تعلیم کے مطابق مذہب اور ملک کے
ساتھ وفاداری میں ہرگز کوئی ٹکراؤ نہیں ہو سکتا.لیکن یہ مسئلہ صرف اسلام سے تعلق
نہیں رکھتا بلکہ انسانی تاریخ کے مختلف ادوار میں
کئی مملکتیں اس مسئلہ سے دو چار رہی
274
Page 287
ہیں.خاص طور پر رومی سلطنت میں عیسائیت کے پہلے تین سو سالوں میں خصوصاً یہ
الزام لگایا جاتا رہا کہ عیسائی اپنے مذہب کے تو وفادار ہیں مگر سلطنت کے غدار ہیں
اسی کا نتیجہ تھا کہ ابتدائی دور کے عیسائی اپنے ہی گھر میں انتہائی بہیمانہ اور غیر انسانی
مظالم کا شکار بنتے رہے.ان پر یہ الزام عائد کیا جاتا تھا کہ وہ غدار ہیں اور قیصر روم
کے وفادار نہیں ہیں.چرچ اور ریاست کے مابین کشمکش نے تاریخ یورپ کی تشکیل
میں ہمیشہ ایک اہم کردار ادا کیا ہے.مثال کے طور پر نپولین بونا پارٹ نے
رومن کیتھولک چرچ پر الزام لگایا کہ یہ لوگوں کو ملک کا غدار بناتا ہے.اس نے
اہل فرانس پر خوب اچھی طرح واضح کر دیا کہ انہیں سب سے پہلے فرانسیسی عوام اور
حکومت کا وفادار بننا پڑے گا اور کسی ویٹیکن پوپ کو فرانس میں رہنے والے رومن
کیتھولکس کے معاملات میں دخل اندازی کی اجازت نہیں دی جائے گی اور نہ ہی
رومن کیتھولکس کو ریاست کے معاملات میں مداخلت کی اجازت ہوگی.حالیہ تاریخ میں جماعت احمدیہ کو انہی وجوہات کی بناء پر پاکستان میں
شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے.پاکستان میں طویل ترین عرصہ تک حکومت کرنے
والے فوجی آمر جنرل محمد ضیاء الحق کے دور میں تو یہاں تک ہوا کہ حکومت نے
احمدیوں کے خلاف بزعم خود ایک قرطاس ابیض شائع کر دیا جس میں یہ دعویٰ کیا گیا
کہ احمدی نہ تو اسلام کے وفادار ہیں اور نہ ہی پاکستان کے.یہ وہی پرانا جنون ہے
جو آج چند نئے سروں میں سمایا ہوا ہے.وہی آگ ہے جو آج کچھ اور سینوں میں
بھڑک رہی ہے.کچھ ہی عرصہ پہلے بدنام زمانہ سلمان رشدی کے معاملہ میں بھی یہی
ہوا.برطانیہ اور یورپ میں رہنے والے مسلمانوں کو اسی مشکل کا سامنا کرنا پڑا.ان
پر الزام لگایا گیا کہ وہ اپنے ملک کے نہیں بلکہ ثمینی کے وفادار ہیں.اگر چہ اس آگ
کے شعلے بہت زیادہ تو نہیں پھیلے لیکن ایسی صورتحال میں جو خطرات پوشیدہ ہیں انہیں
275
Page 288
معمولی نہیں سمجھنا چاہئے.مذہبی جماعتوں کے باہمی تعلقات کو ان سے سخت نقصان
پہنچ سکتا ہے.کیا صرف مذہب ہی کو قانون سازی کا حق حاصل ہے؟
مذہب اور مملکت کا مسئلہ ایک ہمہ گیر اور آفاقی مسئلہ ہے مگر اس پر کبھی پوری
سنجیدگی سے تحقیق نہیں کی گئی.سیاستدان اور مذہبی راہنما دونوں ہی کبھی یہ فیصلہ نہیں
کر پائے کہ وہ حد فاصل کون سی ہے جو مذہب کو مملکت سے جدا کرتی ہے.جہاں تک
عیسائیوں کا تعلق ہے یہ مسئلہ اسی وقت حل ہو جانا چاہئے تھا جب حضرت عیسی
علیہ السلام نے فریسیوں کو ایک تاریخی جواب دیا تھا جو انجیل میں ان الفاظ میں درج
ہے.' تب اس نے انہیں کہا کہ جو قیصر کا ہے قیصر کو دو اور جو خدا کا ہے وہ خدا
کو دو.(متی باب ۲۲ آیت ۲۱)
حضرت عیسی علیہ السلام کا یہ بیان بہت پُر حکمت ہے اس میں ہر ضروری بات
بیان کر دی گئی ہے.مذہب اور سیاست معاشرہ کے دو پہیوں کی طرح ہیں.پیسے خواہ
دو ہوں یا چار یا آٹھ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جب تک سب کل پرزے اپنی اپنی
جگہ پر قائم رہتے ہوئے صحیح سمت میں حرکت کرتے رہیں کسی قسم کے تصادم اور
جھگڑے کا سوال پیدا نہیں ہوگا.قرآن کریم نے صحف سابقہ سے کامل اتفاق کرتے ہوئے اس نظریہ کو مزید
وضاحت سے بیان فرمایا ہے اور نہ صرف معاشرہ کے اجزائے ترکیبی کی حدود کو متعین
کیا ہے بلکہ ان کے دائرہ عمل کی نشاندہی بھی کی ہے.قرآن کریم کی امور مملکت سے
276
Page 289
متعلق تعلیم اور اس کی دی ہوئی دینی تعلیم میں کوئی باہمی تضاد نہیں ہے اگر چہ یہ کہنا بھی
درست نہیں ہوگا کہ مذہب اور مملکت کے مابین کوئی بھی ایسی مشتر کہ سرزمین نہیں ہے
جہاں دونوں کا عمل دخل ہو.بلاشبہ کئی ایسے مقامات ہیں جہاں بیک وقت دونوں اپنا
عمل دخل رکھتے ہیں لیکن یہ عمل باہمی تعاون کی روح کے ساتھ ہے نہ کہ کسی ایک کی
اجارہ داری کے قیام کے لئے.چنانچہ مذہب کی عطا کردہ اخلاقی تعلیم مختلف ممالک
میں ہونے والی قانون سازی کا ضروری حصہ بن جاتی ہے کسی ملک میں کم اور کسی
ملک میں زیادہ.ملکی قوانین میں جرائم کی مجوزہ سزاؤں کے پس منظر میں مذہب کی پسند یا نا پسند
بہر حال موجود ہے.اس کے باوجود جہاں تک مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والوں کا
تعلق ہے وہ اپنے ملک کے بعض سیکولر قوانین سے اختلاف کے باوجود شاذ و نادر ہی
کسی آئینی حکومت کے ساتھ تصادم کا راستہ اختیار کیا کرتے ہیں.اور یہ مسلمانوں
اور عیسائیوں پر ہی موقوف نہیں دیگر مذاہب کے ماننے والوں کا بھی یہی طریق ہے.اس میں کیا شک ہے کہ منوسمرتی (Manusmarti) میں درج ہند و قوانین ہندوستان
کی سیاسی حکومتوں کے بنائے ہوئے سیکولر قوانین سے بالکل مختلف ہیں لیکن وہاں کے
ہند و کسی نہ کسی طرح حالات سے سمجھوتہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں.اگر مختلف
ممالک کے لوگ مذہبی قوانین کی حمایت میں رائج الوقت سیاسی نظام کے مقابل پر
کھڑے ہو جا ئیں تو یقیناً خون کی ندیاں بہہ جائیں مگر بنی نوع انسان کی خوش قسمتی
ہے کہ ایسا ہوتا نہیں.جہاں تک اسلام کا تعلق ہے مذہب اور مملکت کے مابین کوئی
محاذ آرائی نہیں ہے.اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام ہر حالت میں کامل انصاف پر سختی
سے کار بند رہنے کا اٹل اور غیر مبدل اصول پیش فرماتا ہے.ہر اس حکومت کے لئے
جو اسلامی ہونے کا دعویٰ کرتی ہے یہ اصول ایک بنیادی اور مرکزی لائحہ عمل کی حیثیت
277
Page 290
رکھتا ہے.افسوس کہ امور سیاست سے متعلق اسلامی نظریہ کے اس اہم ترین نکتہ کو
سیاسی مفکرین نے اگر کچھ سمجھا بھی ہے تو بہت کم.عام نوعیت کے جرائم اور کسی خاص
مذہبی حکم سے تعلق رکھنے والے جرائم پر قانون کے اطلاق میں جو فرق ہے وہ اسے
نہیں سمجھ سکتے.ظاہر ہے کہ مؤخر الذکر جرائم کی سزا انہیں لوگوں پر نافذ ہو گی جو اس
مذہب کے ماننے والے ہیں.دراصل جرائم کی ان ہر دو اقسام کی معین اور واضح
تعریف نہیں کی گئی ہے.جرم وسزا کی دنیا میں کئی مشترکہ مقامات ایسے ہیں جہاں عمومی
نوعیت کے جرائم بظاہر مذہبی اور اخلاقی جرائم بھی دکھائی دیتے ہیں اور عام طور پر
تسلیم شده انسانی قدروں کے لحاظ سے بھی جرم بن جاتے ہیں.مثال کے طور پر
چوری ایک ایسا جرم ہے جس کی بعض معاشروں میں زیادہ اور بعض میں کم مذمت کی
جاتی ہے.بعض جگہ چوری کی سزا بڑی سخت ہے مگر بعض جگہ اتنی سختی نہیں کی جاتی.اسی
طرح قتل، شراب نوشی اور دنگا فساد جیسے جرائم ہیں جن کو بعض مذاہب نے جزوی طور
پر یا کلیہ ممنوع قرار دیا ہے اور بعض نے ان جرائم کی معین سزائیں بھی تجویز کی
ہیں.اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حکومت کو ایسے جرائم سے کس طرح نپٹنا ہوگا.پھر اسی سے یہ سوال بھی ابھرتا ہے کہ کیا اسلام نے اس سلسلہ میں ایک مسلم یا غیر مسلم
حکومت کو کوئی واضح اور معتین لائحہ عمل دیا ہے؟ اگر اسلام نے حکومت کی کوئی معین شکل
پیش کی ہے تو پھر کئی ایک اور اہم سوالات بھی پیدا ہوں گے.مثلاً یہ کہ کیا کوئی ایسی
مملکت ہو سکتی ہے جو خود کو کسی خاص مذہبی تعلیم کے تابع خیال کرے اور کیا یہ جائز ہوگا
کہ ایسی حکومت اس مذہبی تعلیم کو اپنے تمام شہریوں پر نافذ کرے خواہ وہ اس مذہب
سے تعلق رکھتے ہوں یا نہ رکھتے ہوں.بات یہ ہے کہ مذہب کا فرض قانون سازی
کرنے والوں کی توجہ اخلاقی مسائل کی طرف مبذول کرانا ہے.یہ ہرگز ضروری نہیں
278
Page 291
ہے کہ تمام قانون سازی مذاہب کے تابع ہو.جب صورتحال یہ ہے کہ بالکل مختلف
عقائد رکھنے والے فرقے موجود ہیں اور پھر ہر فرقہ آگے کئی شاخوں میں منقسم ہے، ہر
مذہب دوسرے مذہب سے مختلف عقائد رکھتا ہے تو اس صورت میں قانون سازی کو
مذہب کے تابع کرنے کا نتیجہ سوائے ابتری کے اور کیا ہوسکتا ہے.مثال کے طور پر
شراب نوشی کی سزا ہی کو لے لیجئے.اگر چہ قرآن کریم نے شراب کو حرام قرار دیا ہے
لیکن قرآن کریم نے اس کی کوئی معین سزا بیان نہیں کی.اس کے لئے کچھ ایسی
روایات پر انحصار کیا گیا ہے جو بعض مکاتب فقہ کے نزدیک درست ہی نہیں.اب
اس اختلاف کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک علاقہ یا ملک میں شراب نوشی کی سزا کچھ اور ہوگی
اور دوسرے علاقہ یا ملک میں کچھ اور.پس عوام الناس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اصل
قانون کون سا ہے؟ صرف اسلام ہی نہیں باقی مذاہب کو بھی ایسی ہی صورت حال
در پیش ہوگی.طالمود کا دیا ہوا قانون بھی بالکل نا قابل عمل بن کر رہ جائے گا اور یہی
حال عیسائیت کی دی ہوئی تعلیم کا ہوگا.بات یہ ہے کہ ملکی قانون کے اندر رہتے ہوئے کسی بھی مذہب کا پیروکار اپنے
مذہبی عقائد کے مطابق زندگی گزار سکتا ہے.وہ سچ بول سکتا ہے ریاست کا قانون
اسے سچ بولنے سے منع نہیں کرتا.وہ اپنی عبادات بجا لا سکتا ہے اس بات کی چنداں
ضرورت نہیں کہ ریاست اسے ایسا کرنے کی اجازت دینے کے لئے کوئی خاص
قانون بنائے.اس سوال کا ایک اور دلچسپ زاویہ سے بھی جائزہ لیا جا سکتا ہے.اگر اسلام یہ
کہتا ہے کہ جن ممالک میں مسلمان اکثریت میں ہوں وہاں حکومت اسلامی اکثریت
کی ہونی چاہئے تو پھر کامل انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ دوسرے ممالک کو بھی یہ حق دیا
جائے کہ وہاں کی مذہبی اکثریتیں اپنے اپنے مذہب کے احکامات کے مطابق امور
279
Page 292
مملکت بجالائیں.پاکستان کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ اس کے قریبی ہمسایہ ملک بھارت
میں ہندو قانون ملکی قانون کی حیثیت سے رائج ہو اور تمام شہریوں پر یکساں لاگو ہو.حقیقت یہ ہے کہ جس دن ایسا ہوا وہ دن بھارت کے دس کروڑ مسلمانوں کے لئے
ایک المناک دن ہوگا کیونکہ اس دن وہ سب کے سب بھارت میں باعزت طور پر
زندہ رہنے کے تمام حقوق سے محروم کر دیئے جائیں گے.پھر یہ کہ اگر بھارت میں
منوسمرتی کے مطابق حکومت بن سکتی ہے تو اسرائیل کو یہ حق کیوں نہیں دیا جا سکتا کہ وہ
بھی اپنے ملک میں یہود اور غیر یہود دونوں پر طالمود کے قانون کے مطابق حکومت
کرے اگر واقعہ ایسا ہوا تو نہ صرف اسرائیل کے رہنے والے غیر یہودی شہریوں
کے لئے بلکہ خود یہودیوں کی ایک بڑی تعداد کے لئے بھی زندگی ایک عذاب بن کر
رہ جائے گی.مختلف ممالک میں مذہبی حکومتوں کے قیام کا تصور تبھی درست ہو گا اگر
ساتھ ہی یہ بھی تسلیم کیا جائے کہ جن ممالک میں مسلمان اکثریت میں ہیں وہاں
اسلامی ریاست میں شریعت کو جبراً ڈنڈے کے زور سے نافذ کر دیا جائے.مگر اس
طرح پھر دنیا بھر کو ایک متناقض صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ ایک طرف تو
کامل انصاف کے نام پر تمام ممالک کو یہ حق دیا جائے گا کہ وہ اپنے عوام پر اکثریت
کے مذہب کا قانون مسلط کر دیں، دوسری طرف ہر ملک میں مذہبی اقلیتوں سے ان
کے ہر
فعل پر اکثریت کے مذہبی قانون کے مطابق مواخذہ کیا جائے گا جس پر وہ
ایمان ہی نہیں رکھتیں.پس کیا یہ صورتحال کامل انصاف کے ساتھ اسلامی تصور کی
رسوائی کا موجب نہیں ہو گی ؟ اسلامی شریعت کے نفاذ کی باتیں کرنے والوں نے اس
الجھن اور مخمصہ کے متعلق نہ تو کبھی سوچا ہے اور نہ اسے حل کرنے کی کوشش کی ہے.میرے نزدیک اسلامی تعلیم کا لب لباب یہ ہے کہ امور مملکت کو چلانے کے لئے
بنیادی اصول یہ ہے کہ سب کے ساتھ یکساں اور کامل انصاف کرنا ہے.اگر اس
280
Page 293
اصول پر عمل کیا جائے تو ہر ملک کی حکومت گویا ایک اسلامی حکومت بن جائے گی.ان
دلائل کی روشنی میں اور خاص طور پر لَا إِكْرَاهَ فِی الدِّین جیسے اہم حکم کی موجودگی
میں میں سمجھتا ہوں کہ مذہب کو امور سلطنت اور قانون سازی میں کوئی بالا اختیار
دینے کی ضرورت نہیں.اسلام اور ریاست
قرآن کریم کے گہرے مطالعہ کے بعد میں شرح صدر سے کہہ سکتا ہوں کہ
قرآن کریم جب حکومت کے موضوع پر بات کرتا ہے تو مسلم اور غیر مسلم ممالک میں
امتیاز نہیں کرتا اور امور سلطنت کی بجا آوری کے سلسلہ میں جو معیار قائم کرتا ہے اس
کے اول مخاطب اگر چہ مسلمان ہیں لیکن دراصل مخاطب تمام بنی نوع انسان ہیں.اس ضمن میں قرآن کریم نے جو تعلیم دی ہے وہ ہندوؤں، سکھوں، بدھوں،
عیسائیوں ، یہودیوں، مسلمانوں اور دیگر مذاہب کے پیروکاروں غرضیکہ سب کے لئے
یکساں طور پر قابل عمل ہے.اس تعلیم کا خلاصہ جن آیات میں بیان ہوا ہے ان میں
سے ایک آیت پہلے درج کی جا چکی ہے.اس مضمون کی بعض دیگر آیات درج ذیل
ہیں.فَلا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي
لیک
أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيْمَان
(سورۃ النساء آیت ۶۶)
ترجمہ : نہیں.تیرے رب کی قسم ! وہ کبھی ایمان نہیں لا سکتے جب تک وہ
تجھے ان امور میں منصف نہ بنا لیں جن میں ان کے درمیان جھگڑا ہوا
ہے.پھر تو جو بھی فیصلہ کرے اس کے متعلق وہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہ
281
Page 294
پائیں اور کامل فرمانبرداری اختیار کریں.يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءِ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ
أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْفَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا
ج
الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا : وَإِنْ تَلُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا
(سورۃ النساء آیت ۱۳۶)
ترجمہ:.اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو! اللہ کی خاطر گواہ بنتے ہوئے
انصاف کو مضبوطی سے قائم کرنے والے بن جاؤ خواہ خود اپنے خلاف
گواہی دینی پڑے یا والدین اور قریبی رشتہ داروں کے خلاف.خواہ
کوئی امیر ہو یا غریب دونوں کا اللہ ہی نگہبان ہے.پس اپنی خواہشات
کی پیروی نہ کرو مبادا عدل سے گریز کرو.اور اگر تم نے گول مول بات
کی یا پہلو تہی کر گئے تو یقیناً اللہ جو تم کرتے ہو اس سے بہت باخبر ہے.ہے.احادیث مبارکہ میں اس موضوع پر بڑی وضاحت سے روشنی ڈالی گئی
حضور ﷺ کا ارشاد ہے کہ ہر حاکم اور صاحب امر اللہ تعالیٰ کے حضور براہ راست
اس بات کا جوابدہ ہے کہ وہ اپنی رعایا اور ماتحتوں کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے.چونکہ اس موضوع پر سیر حاصل بحث ہو چکی ہے اس لئے اس پر مزید کچھ کہنے کی
ضرورت نہیں ہے.اس بحث کا لب لباب یہ ہے کہ اسلام ایک ایسی کامل اور غیر جانبدار مرکزی
حکومت کا تصور پیش کرتا ہے جس میں ریاست کے شہری ہونے کے لحاظ سے سب
برابر ہوں اور سب پر قوانین کا یکساں اطلاق ہو اور مذہبی اختلافات کا امور سلطنت
میں کوئی عمل دخل نہ ہو.اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام مسلمانوں کو خبر دار کرتا ہے کہ
وہ دنیوی معاملات میں رائج الوقت قانون کی اتباع کریں.چنانچہ فرماتا ہے:
282
Page 295
يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ، فَإِنْ
رون
ج
تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُوْلِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
o
الأخرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاه
(سورۃ النساء آیت ۶۰)
ترجمہ:.اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو! اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی
اطاعت کرو اور اپنے حکام کی بھی.اور اگر تم کسی معاملہ میں ( اولوالامر
سے ) اختلاف کرو تو ایسے معاملے اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دیا کرو اگر
(فی الحقیقت) تم اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان لانے والے ہو.یہ بہت
بہتر ( طریق) ہے اور انجام کے لحاظ سے بہت اچھا ہے.لیکن جہاں تک خدا اور بندہ کے تعلق کا سوال ہے یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو
مذہب سے مخصوص ہے اور ریاست کو اس میں مداخلت کا کوئی حق حاصل نہیں
ہر شخص پوری طرح آزاد ہے کہ جو عقیدہ چاہے رکھے اور اس کا اظہار کرے.ہر شخص
کا یہ بنیادی حق ہے کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق اللہ تعالیٰ یا کسی بت کی پرستش
کرے.ہے.پس اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ مذہب کا کوئی حق نہیں کہ وہ ان معاملات میں
دخل اندازی کرے جو خالصتاً ریاست کے دائرہ کار میں آتے ہیں نہ ہی حکومت کو یہ
حق حاصل ہے کہ وہ مذہبی معاملات میں مداخلت کرے.اسلام نے جملہ حقوق اور
فرائض کا اتنی وضاحت کے ساتھ تعین کر دیا ہے کہ کسی ٹکراؤ کی صورت پیدا نہیں
ہو سکتی.اس موضوع سے متعلق بہت سی آیات کا مذہبی امن کے ضمن میں ذکر کیا جا چکا
ہے.بدقسمتی یہ ہے کہ بعض دفعہ بہت سے سیکولر ممالک اپنی حدود سے تجاوز کر جاتے
ہیں اور یہی حال مذہبی ریاستوں یا ان ریاستوں کا ہے جن پر مذہب کے ٹھیکیدار
مسلط ہیں.ایسے ممالک جہاں مذہبی جنونیوں کی حکومت ہو ان کے لئے ہمدردی کے
283
Page 296
جذبات تو شاید پیدا نہ ہوں لیکن ان کے ہاں غیر متوازن نظریات کا پایا جانا کسی
حد تک قابل فہم ہے، مگر جب اس قسم کی خام اور طفلانہ حرکات کا مظاہرہ ان سیکولر
ممالک میں بھی کیا جائے جو بزعم خود روشن خیال اور ترقی یافتہ کہلاتے ہیں تو یقین نہیں
آتا.بد قسمتی سے بنی نوع انسان کے سیاسی طرز عمل میں صرف یہی ایک بات نہیں
جسے سمجھنا مشکل ہے حقیقت یہ ہے کہ جب تک سیاست اسی طرح قومی مفادات کی
اسیر رہے گی اور اس کی سوچ قومیت کے تنگ دائرہ سے باہر نہیں نکلے گی اس وقت
تک سیاست میں اصول نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہو گی.جب تک قومی تعصبات
سیاسی فکر پر حاوی رہیں گے اور جب تک قومی مفاد سے تصادم کی صورت میں سچائی ،
دیانت اور عدل و انصاف کو نظر انداز کیا جاتا رہے گا اور حب الوطنی کی یہی تعریف کی
جاتی رہے گی انسانی سیاست اسی طرح مشکوک ، متناقض اور متنازعہ رہے گی.قرآن کریم حکومت اور عوام کی جو ذمہ داریاں بیان فرماتا ہے ان میں سے بعض
کا ذکر پہلے کیا جا چکا ہے مثلاً خوراک، لباس، رہائش اور دیگر بنیادی ضروریات زندگی
کی فراہمی ، عالمی امداد کے اصول، حکومت اور عوام کے احتساب کا طریق کار،
حکومت اور عوام کس طرح ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں؟ حقیقی انصاف کیا
ہے؟ عوام کی تکالیف کا خود احساس کرنا تا کہ انہیں اپنے حقوق کے لئے آواز اٹھانے
کی کوئی ضرورت نہ رہے.یہ سب امور پہلے بیان ہو چکے ہیں.اسلامی نظام میں
حکومت کا یہ فرض ہے کہ وہ عوام کے مسائل سے باخبر رہے اور انہیں اپنے حقوق کے
حصول کے لئے ہڑتالوں کی ضرورت نہ پیش آئے.آجر اور اجیر کے جھگڑے نہ ہوں
اور نہ ہی مظاہروں اور توڑ پھوڑ کی نوبت آئے.قرآن کریم نے ان سب کے علاوہ
بعض اور ذمہ داریاں بھی بیان فرمائی ہیں جن کا اب ہم مختصر ذکر کرتے ہیں.قرآن کریم فرماتا ہے:
284
Page 297
وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةٌ فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوْآءِ ، إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ
الْخَائِنِينَ
(سورۃ الانفال آیت ۵۹)
ترجمہ:.اور اگر کسی قوم سے تو خیانت کا خوف کرے تو ان سے ویسا ہی کر
جیسا انہوں نے کیا ہو.اللہ خیانت کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا.اس سے مراد یہ ہے کہ ایسے طریق پر حکومت نہ کرو جس کے نتیجہ میں فتنہ وفساد
بڑھے اور عوام کے مصائب و مشکلات میں اضافہ ہو.حکومت کا فرض ہے کہ وہ مؤثر
اور مثبت رنگ میں محنت کرے یہاں تک کہ معاشرہ ہر لحاظ سے امن و آشتی کا گہوارہ
بن جائے.ه و
امنْ يُجِيْبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ عَ
W 28
إِلهُ مَّعَ اللَّهِ ، قَلِيلًا مَّاتَذَكَّرُونَ
(سورۃ النمل آیت ۶۳ )
ترجمہ:.یا (پھر) وہ کون ہے جو بے قرار کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ اسے
پکارے اور تکلیف دور کر دیتا ہے اور تمہیں زمین کا وارث بناتا ہے.کیا اللہ
کے ساتھ کوئی (اور ) معبود ہے؟ بہت کم ہے جو تم نصیحت پکڑتے ہو.بین الاقوامی تعلقات کی بنیاد کامل انصاف پر ہے
حقیقت یہ ہے کہ آج ہر سیاست دان چھوٹا ہو یا بڑا اس سلسلہ میں اسلامی
تعلیمات کی راہنمائی کا محتاج ہے.اسلام ہی وہ مذہب ہے جس میں بین الاقوامی
معاملات کی بنیاد کامل عدل و انصاف پر رکھی گئی ہے.چنانچہ فرمایا.يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُوْنُوْا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ
قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا وَ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ
بِمَا تَعْمَلُوْنَ
قف
ده
(سورة المائدة آیت ۹)
285
Page 298
ترجمہ: اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو! اللہ کی خاطر مضبوطی سے نگرانی
کرتے ہوئے انصاف کی تائید میں گواہ بن جاؤ اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں
ہرگز اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو.انصاف کرو یہ تقویٰ
کے سب سے زیادہ قریب ہے اور اللہ سے ڈرو.یقیناً اللہ اس سے ہمیشہ
باخبر رہتا ہے جو تم کرتے ہو.میں یہ دعویٰ تو نہیں کرتا کہ میں نے دنیا کے تمام بڑے بڑے مذاہب کے متعلق
سب کچھ مطالعہ کر رکھا ہے مگر میں ان مذاہب کی تعلیمات سے بالکل لاعلم بھی نہیں
ہوں.مجھے ان مذاہب کی کتب میں کوئی ایک بھی ایسا حکم نہیں ملا جو اس قرآنی آیت
کے معیار پر پورا اترتا ہو.دیگر مذہبی کتب کا تو یہ حال ہے کہ ان میں بین الاقوامی
تعلقات کا ذکر شاذ و نادر کے طور پر ہی ملتا ہے تاہم اگر کسی اور مذہب میں بھی ایسی
ہی تعلیم پائی جاتی ہو تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اسلام اس تعلیم سے پورے طور
پر اتفاق کرتا ہے کیونکہ یہی وہ تعلیم ہے جو عالمی امن کے سلسلہ میں کلیدی حیثیت رکھتی
ہے.آج ساری دنیا امنِ عالم کے مستقبل کے متعلق فکر مند ہے.سوشلسٹ دنیا میں
رونما ہونے والے عہد ساز تغیرات اور عالمی طاقتوں کے باہمی تعلقات میں بہتری
سے امید کی ہلکی سی جھلک نظر آتی ہے.لوگ بڑے خوش دکھائی دے رہے ہیں.ہمارے ارد گرد جو انقلابی تبدیلیاں پیدا ہو رہی ہیں ان کے ممکنہ نتائج کے بارہ میں دنیا
بھر کے سیاسی راہنما نہ صرف انتہائی پر امید ہیں بلکہ ضرورت سے زیادہ خوش نظر
آ رہے ہیں خصوصیت سے مغربی دنیا تو کچھ زیادہ ہی پر اعتماد ہے اور خوشی سے پھولی
نہیں سما رہی.امریکیوں کی تو باچھیں کھلی جا رہی ہیں انہیں اپنے جذبات مسرت کو
سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے.وہ اشترا کی دنیا پر اپنی اس عظیم الشان فتح کے شادیانے بجا
286
Page 299
رہے ہیں اور بعض لوگ تو اسے خیر کی شر پر اور حق کی باطل پر فتح قرار دے رہے
ہیں.یہاں دنیا بھر کی جغرافیائی اور سیاسی صورت حال کا مفصل تجزیہ پیش کرنے کا
موقع تو نہیں تاہم جولائی ۱۹۹۰ ء کے آخر میں جماعت احمد یہ برطانیہ کے جلسہ سالانہ
کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو میں اس موضوع پر تفصیل سے بات کروں گا.اقوام متحدہ کا کردار
دنیا میں رونما ہونے والے حالیہ واقعات اور عالمی امن کے مستقبل پر جگہ جگہ جو
بحث و تمحیص جاری ہے اس کا یہ پہلو خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ اقوام متحدہ کو
امنِ عالم کے قیام اور اس کے تحفظ کے سلسلہ میں پہلے سے کہیں زیادہ مؤثر طور پر ادا
کرنا ہو گا.دوسپر طاقتوں کے مابین سرد جنگ کے خاتمہ کے بعد امید کی جا رہی ہے کہ
عالمی مسائل کے بارہ میں ان کا موقف ایک سا ہو جائے گا جس کے نتیجہ میں سلامتی
کونسل میں ویٹو کے حق کا استعمال بھی کم ہو جائے گا اور عالمی مسائل باہمی رضا مندی
سے طے ہونے لگیں گے اور یوں سلامتی کونسل مستقبل میں ایک نئے روپ میں ہمارے
سامنے آئے گی البتہ چین کے متعلق اندیشہ ہے کہ وہ شاید اس نئی صورت حال میں
جذب نہ ہو سکے.تاہم اس کے پیچیدہ اقتصادی اور سیاسی مسائل کی موجودگی میں اسے
بڑی طاقتوں کے ساتھ تعاون پر آمادہ کر لینا اتنا ناممکن بھی نہیں ہے.چین کے متعلق
ہما را اندازہ درست ثابت ہوتا ہے یا نہیں یہ ایک الگ بحث ہے لیکن یہ صاف دکھائی
دے رہا ہے کہ آنے والے سالوں میں سیکیورٹی کونسل اور خود اقوام متحدہ واقعات عالم
پر اپنی گرفت کے لحاظ سے ایک طاقتور سیاسی آلہ کار بن کر ابھرنے والی ہے جس کے
ذریعہ چھوٹی اقوام کو بڑی طاقتوں کی مرضی کے سامنے جھکنے پر مجبور کیا جائے گا.واقعہ یہ
287
Page 300
ہے کہ دیوار برلن کے گرنے سے پہلے تو ایسی صورت حال کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا
تھا.بہر حال یہ سوال اپنی جگہ پر موجود ہے کہ کیا اقوام متحدہ اپنے موجودہ عظیم عدالتی
اور انتظامی اختیارات کے ساتھ عالمی امن کے خواب کو حقیقت میں بدل سکتی ہے؟
میرے نزدیک اس سوال کا جواب نفی میں ہے.اگر اس جواب میں آپ کو قنوطیت نظر
آئے تو میں معذرت خواہ ہوں.بات یہ ہے کہ دنیا میں امن اور جنگ کے فیصلے محض
بڑی طاقتوں کے باہمی تعلقات پر ہی منحصر نہیں ہوا کرتے بلکہ یہ ایک بہت گہرا اور
پیچیدہ مسئلہ ہے جس کی جڑیں قوموں کے سیاسی اور اخلاقی رجحانات میں پیوست ہیں.مزید برآں دنیا میں پایا جانے والا اقتصادی تفاوت اور امیر اور غریب ممالک
کے درمیان بڑھتا ہوا بُعد بھی مستقبل میں رونما ہونے والے واقعات کے سلسلہ میں
لازماً ایک بے حد اہم اور مؤثر کردار ادا کرے گا جس کے بعض پہلوؤں کا ذکر پہلے کیا
جا چکا ہے.یہ بات بہر حال یقینی ہے کہ جب تک اقوام متحدہ کے تمام رکن ممالک کے
مابین اقتصادی تعلقات میں کامل انصاف کے اصول کو نہیں اپنا یا جاتا اور جب تک
اسے عملاً نافذ نہیں کیا جاتا امن کی کوئی ضمانت نہیں دی جاسکتی.جب تک اقتصادی اور
تجارتی ناانصافیاں ہوتی رہیں گی اور غریب ممالک کی دولت کو لوٹا جاتا رہے گا
عالمی امن کی ضمانت کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا نیز جب تک رکن ممالک کے ساتھ
اقوام متحدہ کے تعلق اور کردار کا واضح طور پر تعین نہیں ہو جاتا امن عالم کا مستقبل تاریک
رہے گا.ضرورت ایسے اقدامات کرنے کی ہے جن کے ذریعہ حکومتوں کو اپنے عوام پر ظلم وستم
ڈھانے سے باز رکھا جا سکے.اقوام متحدہ کے پاس کچھ ایسے اختیارات اور طریق کار
ہونا چاہیے جس سے وہ دنیا میں کسی بھی جگہ ہونے والی ناانصافی کے خلاف ایک
منصفانہ اور مؤثر جہاد کر سکے.جب تک ایسا نہیں ہوتا امن عالم کا خواہ
288
Page 301
شرمندہ تعبیر نہیں ہوسکتا.یہ ایک بڑا نازک مگر عالمی امن کے قیام کے لئے بہت ضروری سوال ہے کہ
اقوام متحدہ کسی ملک کے داخلی معاملات میں کس حد تک مداخلت کر سکتی ہے لیکن یہ بات
طے ہے کہ اگر اقوام متحدہ کی پالیسی کامل انصاف پر مبنی نہ ہو اور سب قوموں کے
ساتھ برابری کی بنیاد پر سلوک نہ کیا جائے تو اس صورت میں اقوام متحدہ کو مختلف ملکوں
کے اندرونی معاملات میں مداخلت کے مزید اختیارات دینے سے مسائل پیدا زیادہ
ہوں گے اور حل کم ہوں گے.پس یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس پر ٹھنڈے دل کے
ساتھ غیر جانبدارانہ طور پر تفصیل سے غور ہونا چاہئے.اب تک جو ہوا وہ یہ ہے کہ سوویت یونین اور مشرقی بلاک یہ اعتراف کرنے پر
مجبور کر دیئے گئے ہیں کہ سائینٹیفک سوشلزم کے سب فلسفے ان کی زندگی کو بہتر بنانے
میں ناکام ہو چکے ہیں.اس اعتراف ناکامی سے صورت حال بے حد پیچیدہ ہوگئی
ہے.آئندہ واقعات عالم کیا رنگ اختیار کریں گئے یہ دیکھنے کے لئے ہمیں ابھی
کچھ دیر اور انتظار کرنا پڑے گا.ابھی ہم یہ نہیں جانتے کہ کیا سوشلزم کلیۂ پسپا ہو
جائے گا اور کیا ساری دنیا سرمایہ دارانہ نظام کی طرف پاگلوں کی طرح سرپٹ دوڑ پڑے
گی یا ایک ملے جلے مخلوط اقتصادی نظام کے نئے تجربات کئے جائیں گے.ابھی ہمیں یہ
علم نہیں ہے کہ کیا آمرانہ حکومتوں کا سخت گیر مرکزی کنٹرول ختم ہو جائے گا یا ایسی
حکومتیں پارہ پارہ ہو جائیں گی جس کے نتیجہ میں انار کی اور طوائف الملوکی کی سی
صورت حال پیدا ہو جائے گی.یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آمرانہ حکومتوں کا کنٹرول رفتہ رفتہ
فرد اور سیاست کے مابین' کچھ لو کچھ دو کی بنیاد پر ایک نئے مفاہمتی نظام میں تبدیل
ہو جائے اور رفتہ رفتہ شہری آزادیاں واپس مل جائیں اور بنیادی انسانی حقوق کو
بحال کر دیا جائے.صدر گوربا چوف کے نظریات پر سٹرائیکا (Perestroika) (یعنی
289
Page 302
روس کی سیاسی اور اقتصادی تشکیل نو ) اور گلاسنوسٹ (Glasnost) (یعنی حکومتی
معاملات میں اظہار کی آزادی اور کھلا پن اور کٹر کمیونسٹوں کے مابین جاری کشمکش
کا نتیجہ کیا ہو گا؟ یہ دیکھنے کے لئے ابھی کچھ اور انتظار کرنا پڑے گا.جہاں تک مجھے علم ہے روس کے غیر طبقاتی معاشرہ میں اکثر مراعات
کمیونسٹ پارٹی کے عہدہ داروں، نوکر شاہی اور مسلح افواج نے آپس میں بانٹی ہوئی
ہیں.اہم ترین سوال یہ ہے کہ اب جس انقلاب کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو گئے
ہیں اور جو نازک مرحلہ در پیش ہے اس میں یہ سب لوگ کیا کردار ادا کریں گے.روس میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کے عالمی امن پر امکانی اثرات کا اندازہ کرنے
کے لئے پہلے ایسے تمام سوالات کا جواب دینا ضروری ہے.دو بڑی طاقتوں کے
مابین کشیدگی کی کمی سے امن کی امیدیں وابستہ نہیں کی جاسکتیں اس سے تو بالخصوص
تیسری دنیا کے ممالک کئی قسم کے مہیب خطرات کی زد میں آگئے ہیں.حقیقت یہ ہے کہ ان طاقتوں کے مابین پائی جانے والی بد اعتمادی کے باعث کمزور
اقوام کو ایک قسم کا تحفظ ملا ہوا تھا.ان حالات میں کمزور قو میں کم از کم اپنی وفاداریاں تو
تبدیل کر سکتی تھیں ان کے بس میں اتنا تو تھا کہ وہ چاہیں تو مشرق کا رخ کر لیں اور
چاہیں تو مغرب کی راہ اختیار کر لیں.ان حالات میں وہ کچھ نہ کچھ ہوشیاری اور چالا کی
سے بھی کام لے سکتے تھے اور کچھ سودے بازی بھی کر سکتے تھے لیکن بڑی طاقتوں کے
ما بین محاذ آرائی کے خاتمہ سے اب صورت حال یکسر بدل گئی ہے.حقیقت یہ ہے کہ
ان کمزور اقوام کے پاس آزاد قوموں کی حیثیت سے باعزت طور پر زندہ رہنے کی کوئی
امید باقی نہیں رہی.لامحالہ اس مرحلہ پر ذہن اقوام متحدہ کی جانب منتقل ہو جاتا ہے.اب لے دے کے بظاہر اقوام متحدہ ہی امن عالم کی واحد محافظ ہے اور دنیا میں کسی
نظام نو (New World Order) کے قیام کے لئے امید کی واحد کرن ہے.کاش یہ
290
Page 303
امید بر آئے.لیکن حقائق کو قریب سے اور ناقدانہ نظر کے ساتھ دیکھا جائے تو ایک
تاریک، مایوس کن اور مہیب تصویر ابھرتی ہے.کیا یہ حقیقت نہیں کہ اب دنیا میں طاقت
کا جو نیا توازن پیدا ہوا ہے اس میں اقوام متحدہ کے نظام کو چلانے والی عظیم عالمی
طاقت عملاً ایک ہی ہو گی ؟ ان حالات میں چھوٹی اور کمزور اقوام کا مقدر اس جانور کا
سا ہی ہو سکتا ہے جسے چاروں طرف سے شکاریوں نے گھیر لیا ہو اور اس کے لئے کوئی
راہ فرار باقی نہ رہ گئی ہو.موجودہ صورت حال میں اقوام متحدہ کے متعلق یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ یہ وہ
طاقتور تنظیم ہے جو انصاف کے لئے نہیں بلکہ اس قوم کے سیاسی مقاصد کی خاطر کام
کرتی ہے جس کا حلقہ اثر سب سے وسیع ہو.مجھے یاد نہیں کہ اقوام متحدہ کے حالیہ
فیصلوں میں حق اور باطل کے تصور نے کبھی کوئی با معنی کردار ادا کیا ہو اور نہ ہی اس
کے موجودہ نظام کو دیکھتے ہوئے مستقبل کے متعلق کوئی امید کی جاسکتی ہے.عصر حاضر
میں سیاست اور ڈپلومیسی یوں لازم وملزوم ہو چکی ہیں کہ عدل و انصاف کے قیام اور
اس کی بقاء کا کوئی امکان ہی باقی نہیں رہا.اس تلخ حقیقت کا کوئی انسان جس کے دل
میں سچ کا احترام باقی ہے انکار نہیں کر سکتا کہ سیاست جیسا عظیم اور قابل احترام ادارہ
اب محض پیچ در پیچ ڈپلومیسی، جتھہ بندی، خفیہ تعلقات اور حصول اقتدار کے لئے کی
جانے والی ریشہ دوانیوں کا نام رہ گیا ہے اور ستم یہ ہے کہ یہ سب کچھ عالمی امن کے نام
پر ہو رہا ہے.قرآن کریم کے نزدیک دنیا کو آج ایک ایسے ادارہ کی ضرورت ہے جس کا کام
صرف عدل اور انصاف کو قائم کرنا ہو کیونکہ عدل و انصاف کے قیام کے بغیر امن کا
تصور بھی نہیں کیا جا سکتا.بزعم خود امن اور آزادی ضمیر کے نام پر جنگ تو برپا کی
جاسکتی ہے مگر اس کا نتیجہ سوائے ہلاکت اور بربادی کے کچھ اور نہیں نکل سکتا.افسوس تو
291
Page 304
یہ ہے کہ آج دنیا بھر کے عظیم سیاست دانوں میں سے محض گنتی کے چند نام ہوں گے
جو ہلاکت اور امن کے فرق کو سمجھتے ہیں.ہلاکت نتیجہ ہے طاقتور کے ہاتھوں نا انصافی
جبر و استبداد اور ظلم و ستم کا جبکہ امن و آشتی عدل و انصاف کے نتیجہ میں پیدا ہوتی
ہے.قرآن کریم میں کئی بار امن کا ذکر آیا ہے اور ہر بار یہ ذکر عدل و انصاف کے
ضمن میں کیا گیا ہے.بالعموم امن کو عدل و انصاف کے قیام کے ساتھ مشروط قرار
دیا گیا ہے.دو مسلمان افراد یا اقوام کے مابین اختلاف اگر جنگ اور محاذ آرائی کی
شکل اختیار کرے تو قرآن کریم نے اس کا مندرجہ ذیل حل تجویز فرمایا ہے.وَإِنْ طَائِفَتَنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۚ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدُهُمَا عَلَى
الأخرى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا
ج
بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ
فَأَصْلِحُوابَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
وه
(سورۃ الحجرات آیات ۱۰-۱۱)
ترجمہ :.اور اگر مومنوں میں سے دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو ان
کے درمیان صلح کرواؤ.پس اگر ان میں سے ایک دوسری کے خلاف
سرکشی کرے تو جو زیادتی کر رہی ہے اس سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے
فیصلہ کی طرف لوٹ آئے.پس اگر وہ لوٹ آئے تو ان دونوں کے
درمیان عدل سے صلح کرواؤ اور انصاف کرو.یقیناً اللہ انصاف کرنے
والوں سے محبت کرتا ہے.مومن تو بھائی بھائی ہی ہوتے ہیں.پس اپنے
دو بھائیوں کے درمیان صلح کروایا کرو.اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرو تا کہ تم
پر رحم کیا جائے.ان آیات کریمہ میں مومنوں کا ذکر ہے.غیر مسلموں کا ذکر نہ کرنے کی واضح
وجہ یہ ہے کہ ان سے توقع نہیں کی جاسکتی کہ وہ قرآن کریم کی اطاعت کا جوا اٹھائیں
292
Page 305
گے.بایں ہمہ یہ بھی درست ہے کہ ان آیات میں بیان فرمودہ تعلیم ساری دنیا کے
لئے ایک بہترین ماڈل کے طور پر کام دے سکتی ہے.آج دنیا یہ امید لگائے بیٹھی ہے کہ عالمی تنازعات کے حل کے لئے اقوام متحدہ
اور سلامتی کونسل پہلے سے کہیں زیادہ فعال، مؤثر، وسیع اور با معنی کردار ادا کرے گی
اور کرہ ارض امن و سلامتی کا گہوارہ بن جائے گا یہ سب امیدیں اپنی جگہ لیکن ماضی
میں اقوام متحدہ کی کارکردگی کو دیکھا جائے تو یہ خواب شرمندہ تعبیر ہوتا دکھائی نہیں
دیتا.آج دنیا ایک عجیب منظر پیش کر رہی ہے.اپنے مد مقابل پر برتری حاصل
کرنے کے لئے ہر قسم کے جائز و ناجائز ہتھکنڈے استعمال کئے جاتے ہیں، سازشیں
کی جاتی ہیں، جتھے بنائے جاتے ہیں، پریشر گروپس بنانے کے لئے ڈپلومیسی کی انتہا کر
دی جاتی ہے سیاست کی یہ وہ دنیا ہے جہاں دیانت اور شرم و حیا بے معنی ہو کر رہ گئے
ہیں اور جہاں ضمیر کا داخلہ ممنوع ہے.ایسا ادارہ (اپنے اختلاف اور تضادات کے
با وجود ) قوموں کا ایک جم غفیر تو کہلا سکتا ہے مگر اسے اقوام متحدہ کہنا ایک سنگین مذاق
سے کم نہیں.اگر اسے اتحاد کہتے ہیں تو میں ایسی اقوام میں رہنے کا خطرہ مول لے
لوں گا جو بے شک باہمی تفرقہ کا شکار ہیں لیکن کم از کم صدق اور عدل و انصاف کے
معاملہ میں تو متحد ہیں.اپنے دشمنوں اور مخالفوں کو کچلنے کے لئے طاقت حاصل کرنا اور باتیں امن کی
کرنا.قول و فعل میں یہ تضاد ہی وہ اہم ترین مسئلہ ہے جسے ہر قوم اور ہر ملک کوحل
کرنا ہوگا.یہ حیرت اور دکھ کی بات ہے کہ اقوام متحدہ جیسے شاندار ادارہ کے رکن
ممالک نہ جانے کب تک ان خطرات سے آنکھیں بند کئے بیٹھے رہیں گے جو اس
طریق میں مضمر ہیں جس کے مطابق آج کل اقوام عالم کے معاملات کو چلایا جا رہا
293
Page 306
ہے.آج امن عالم کا مستقبل غیر یقینی ہو چکا ہے اور اس موہوم سی امید سے وابستہ
ہے کہ شاید ایک دن دنیا میں عدل و انصاف کا دور دورہ ہو جائے.294
Page 307
.....مسابقت في الخيرات
انفرادی امن
اعزہ اور اقرباء کے ساتھ محبت.....خدمت خلق...رضائے باری تعالیٰ کا حصول
لوگوں کے دکھ درد سے ہمیشہ باخبر رہنا
محبت و شفقت کا وسیع دائرہ
تخلیق انسانی کا مقصد
اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کوئی امن نصیب نہیں ہوسکتا
295
Page 309
الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللهِ
تَطْمَئِنُّ الْقُلُوب
(سورۃ الرعد آیت ۲۹)
ترجمہ:.(یعنی) وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کے دل
اللہ کے ذکر سے مطمئن ہو جاتے ہیں.سنو! اللہ ہی کے ذکر
سے دل اطمینان پکڑتے ہیں.297
Page 311
میرے خطاب کا آخری حصہ جو انفرادی امن سے متعلق ہے کسی بھی طرح کم اہمیت
کا حامل نہیں ہے.معاشرہ پر امن ہو یا پر آشوب، فرد اس کی تشکیل میں انتہائی اہم
کردار ادا کرتا ہے.اب تک ہم نے معاشرہ کے ان مذہبی، سماجی، اقتصادی اور سیاسی
خد و خال کا جائزہ لیا ہے جن کی تشکیل اور تہذیب اسلام کرنا چاہتا ہے.ایک عمارت کی
تعمیر میں جس طرح عمدہ اینٹوں کی بھی ضرورت ہوا کرتی ہے اسی طرح اسلام کے
نزدیک ایک اچھے معاشرہ کی تعمیر و تشکیل میں افراد کے اعلیٰ کردار اور اوصاف کی بھی
ضرورت ہوا کرتی ہے.یہ ایک بہت وسیع مضمون ہے جس پر قرآن کریم میں اوّل
سے آخر تک بحث اور راہنمائی موجود ہے.اسلام جو اعلیٰ اخلاق اور اوصاف معاشرہ
کے ہر فرد میں پیدا کرنا چاہتا ہے ان میں سے چند ایک درج ذیل ہیں.مسابقت في الخيرات
اسلام نے الہی تعلیم کے مطابق انسانی خواہشات کی تہذیب و تعدیل کرنے کے
ساتھ ساتھ انہیں ابھارا بھی ہے تا کہ مکمل توازن اور اعتدال قائم کیا جا سکے.ایسے
توازن کے بغیر معاشرتی امن کا حصول ناممکن ہے.اسلام ایسی خواہشات کو فروغ
دیتا ہے جن کی تکمیل کسی فرد کی مالی حیثیت پر منحصر نہ ہو اور ہر حیثیت کے لوگ ان
خواہشات کو بلا خرچ یا بہت معمولی خرچ سے پورا کر سکیں.دوسروں سے ممتاز دکھائی دینا اور عوام کے معیار زندگی سے بلند ہونا ایک
طبیعی جذبہ ہے.تاہم دوسروں سے آگے نکلنے کا یہ طبعی رجحان اگر مناسب اور جائز
حدود سے تجاوز کر جائے اور بے لگام ہو جائے تو ایک غیر صحتمند رجحان اور جنون کی
شکل اختیار کر لیتا ہے.مثال کے طور پر حسد یا ناجائز ذرائع کے استعمال.ނ
299
Page 312
مسابقت کی کوشش ایسی برائیاں ہیں جو آزاد اور صاف ستھرے مقابلہ کی روح کے
لئے زہر قاتل کا حکم رکھتی ہیں.ایسی برائیوں کے ہوتے ہوئے مسابقت کا مفید جذبہ
الٹا سارے معاشرہ کو بیمار کر دیتا ہے.اس کی چھوٹی سی مثال کھیلوں کے مقابلوں کے
دوران نشہ آور ادویات کا استعمال ہے.قومی اور بین الاقوامی سطح پر صنعتی اور تجارتی
مقابلوں میں اس کی بہت ہی بری اور گھناؤنی مثالیں ملتی ہیں جہاں انصاف نام کی چیز
نہیں ملتی.یاد رہے کہ تیسری دنیا کے ممالک کے ناجائز ذرائع ترقی یافتہ اقوام کے
اختیار کردہ ناجائز ذرائع سے مختلف ہوتے ہیں.تیسری دنیا کے ممالک میں فوری
اقتصادی فوائد حاصل کرنے کے لئے ناجائز ذرائع بلا تکلف اور بکثرت استعمال کئے
جاتے ہیں مثلاً بد عنوانی ملاوٹ، بد عہدی، فراڈ اور دھوکہ بازی وغیرہ.یہی وجہ ہے کہ
تمام شعبہ ہائے زندگی میں مذہبی اور اخلاقی تعلیم کو بروئے کار لانے کی اشد ضرورت
ہے.ظاہر ہے کہ اس تعلیم کے فقدان سے نہایت خطرناک نتائج نکلنے کا خطرہ ہے.مسابقت سے متعلق مختلف مقابلوں کے سلسلے میں اسلام نے تفصیلی ہدایات دی
ہیں.یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ خود مسلمان ممالک میں جہاں اسلامائزیشن اور
اسلامی بنیاد پرستی کا اس قدر چرچا رہتا ہے وہاں بھی صنعت و تجارت اور
اقتصادی تعلقات کو اسلامی طرز پر ڈھالنے کی کوئی سنجیدہ کوشش شاذ و نادر کے طور پر
ہی دکھائی دیتی ہے.قرآن کریم کی مندرجہ ذیل آیت میں مسابقت کے طبعی جذر
کے متعلق اسلامی تعلیم کا خلاصہ پیش کیا گیا ہے:
وَلِكُلِّ وَجْهَة هُوَ مُوَلَيْهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ، أَيْنَ مَاتَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللهُ
جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرِهِ ( سورة البقرة آیت ۱۴۹)
ترجمہ:.اور ہر ایک کے لئے ایک مطمح نظر ہے جس کی طرف وہ منہ پھیرتا
ہے.پس نیکیوں میں ایک دوسرے پر سبقت لے جاؤ.تم جہاں کہیں بھی
300
Page 313
ہو گے اللہ تمہیں اکٹھا کر کے لے آئے گا.یقیناً اللہ ہر چیز پر جسے وہ
چاہے دائمی قدرت رکھتا ہے.یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے کہ اس مختصر سی آیت میں حکمت کے سمندر کو کوزے میں
بند کر دیا ہے.یہ آیت ہر میدان اور ہر قسم کے مقابلہ کے لئے راہنما اصول مہیا کرتی
ہے.آخری مقصد تو نیکی کا حصول ہے اور یہی دراصل سب سے اعلیٰ و ارفع مقصد
ہے.اس لئے نیکی ہی کو مقابلوں کا مقصود بالذات ہونا چاہئے.پس اس مختصر سی
آیت کے ذریعہ ہر قسم کے ناجائز ذرائع اور ہیرا پھیری سے مسابقت کی کوشش کو کلیپ
ممنوع قرار دے دیا گیا ہے.اگر وقت اجازت دیتا تو ہم تفصیل سے اور وضاحت کے ساتھ یہ جاننے کی
کوشش کرتے اور اسلامی تعلیم سے نظائر پیش کرتے کہ جملہ مقابلوں کو کس طرح
صحتمند، صاف ستھرا اور شفاف رکھا جا سکتا ہے.بہت کم لوگ یہ شعور رکھتے ہیں کہ
قلب و ذہن کا حقیقی اطمینان دراصل نیک ہونے میں ہے نہ کہ ناجائز ذرائع سے کام
لے کر کوئی بڑا معرکہ سرانجام دینے میں.ایسے لوگ نہ تو معاشرہ سے اور نہ ہی اپنی
ذات سے کبھی مطمئن ہوتے ہیں.سرسری نظر سے دیکھنے والوں کو ایسے لوگ بظاہر
بڑے تمھیں مارخان اور خوش و خرم دکھائی دیں گے مگر اندر سے ان کی فتح اور کامیابی
بہت کھو کھلی ہوا کرتی ہے.پاکستان کے ایک مرحوم ارب پتی کے ایک دوست نے مجھے یہ حیران کن اور دکھ بھری
کہانی سنائی کہ ایک مرتبہ اس نے اپنے دوست کے سامنے اس کی عظیم الشان
کامیابیوں کی تعریف کی تو بجائے خوش ہونے کے اس نے جو فوری ردعمل دکھایا وہ
بڑا ہی حیران کن تھا.اس نے اپنا گریبان کھولا اور اپنے ہاتھ کو اس طرح حرکت دی
جیسے وہ اپنے ناخنوں سے جانور کے پنجے کی طرح اپنا سینہ چاک کرنا چاہتا ہے.اس
301
Page 314
نے چھینتے ہوئے کہا کہ میں اس کامیابی پر لعنت بھیجتا ہوں اگر کوئی میرا سینہ چیر کر دیکھ
سکے تو اسے اندر صرف ایک بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلے دکھائی دیں گے.اس تلخ حقیقت کا کچھ لوگ تو اعتراف کر لیتے ہیں مگر کچھ نہیں کرتے لیکن
فطرتِ انسانی کو کون شکست دے سکتا ہے.ایک شخص دولت کا انبار تو لگا سکتا ہے اور
تعیش کے ذرائع تک رسائی بھی حاصل کر لیتا ہے لیکن یہ افسوسناک حقیقت اپنی جگہ
پر موجود ہے کہ شاید ہی چند ایک امیر لوگ ایسے ہوں گے جنہیں حقیقی راحت اور
اطمینان میتر ہو.ان کی حالت کو قرآن کریم نے یوں بیان فرمایا ہے:
ن
وبل لِكُلِّ هُمَزَةٍ تُمَزَةِ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَّ عَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ
مل
أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوْقَدَةُ
،
الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مَوْصَدَةٌ هِ فِي عَمَدٍ سَمَدَدَةِ
(سورة الهمزة آيات ۲ تا ۱۰)
ترجمہ:.ہلاکت ہو ہر غیبت کرنے والے سخت عیب جو کے لئے جس نے
مال جمع کیا اور اس کا شمار کرتا رہا.وہ گمان کیا کرتا تھا کہ اس کا مال اسے
دوام بخش دے گا.خبردار! وہ ضرور حطمہ میں گرایا جائے گا.اور تجھے کیا
بتائے کہ حطمہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی آگ ہے بھڑکائی ہوئی جو دلوں پر لپکے
گی.یقیناً وہ ان کے خلاف بند رکھی گئی ہے ایسے ستونوں میں جو کھینچ کر
لمبے کیے گئے ہیں.جب تک انسان کے اس فطری جذبہ کی تسکین نہیں ہوتی کہ وہ نیک بنے
نیک اعمال بجالائے اور پاکیزہ زندگی بسر کرے اسے سچا اطمینان نصیب نہیں ہو سکتا.اعزہ واقرباء کے ساتھ محبت
ایک مربوط خاندانی نظام اور سماجی امن کے قیام کے لئے اعزہ و اقرباء سے
302
Page 315
محبت و اخوت، صلہ رحمی اور حسن سلوک کی ضرورت کا ذکر کیا جا چکا ہے یہاں اس کا
ذکر اس لئے کیا جا رہا ہے تا کہ فرد کے کردار کی اہمیت اور ضرورت کو اجاگر کیا
جائے.دراصل فرد کا کردار معاشرہ میں وہی مقام رکھتا ہے جو کسی عمارت کی تعمیر میں
اینٹ کا ہوتا ہے.اینٹ کو بہتر بنائے بغیر عمارت کو بہتر نہیں کیا جا سکتا.خدمت خلق
اسلام نے اس امر پر زور دیا ہے کہ انسان کو اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کرنی چاہئے
کہ وہ دوسروں کی خدمت کر کے خوشی محسوس کرے نہ کہ دوسروں سے خدمت لے کر.قرآن کریم کی ایک آیت کے مندرجہ ذیل حصہ میں یہی پیغام دیا گیا ہے.اللہ تعالیٰ
فرماتا ہے:
كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
ط
وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ * (سورۃ آل عمران آیت ۱۱۱)
ترجمہ :.تم بہترین امت ہو جو تمام انسانوں کے فائدہ کے لئے نکالی گئی
ہو.تم اچھی باتوں کا حکم دیتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو اور اللہ
پر ایمان لاتے ہو.اس آیت میں یہ اشارہ کیا گیا ہے کہ ایک مسلمان کو دوسروں پر بلا وجہ فوقیت نہیں
دی گئی.کسی مرد یا عورت کے محض مسلمان ہونے سے خود بخود یہ نتیجہ نہیں نکالا جا سکتا
کہ وہ دوسروں سے بہتر ہے.كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ کا خطاب دوسرے کی خدمت کر کے ہی
حاصل کیا جا سکتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوسروں کے ساتھ احسان کا سلوک
کرنے والے ہوں.303
Page 316
خیر کے معانی بہتر اور بہترین دونوں کے ہیں.ایک مرتبہ آنحضرت ﷺ نے
خیر کے معنوں کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا.اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے.اوپر والا ہاتھ دینے اور
خرچ کرنے والا ہے اور نچلا ہاتھ مانگنے اور لینے والا ہے.“
(صحیح البخارى كتاب الزكاة باب لاصدقة الا عن ظهر غنى -
وصحيح مسلم كتاب الزكاة - باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى)
قرآن کریم اور احادیث میں عظمت کردار کے اس پہلو پر بڑا زور دیا گیا ہے.یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام نے اس تعلیم پر عمل کرتے ہوئے عظمتِ کردار کے نئے اور
ارفع معیار قائم کئے.انہیں بس ایک ہی دھن تھی اور وہ یہ کہ دوسروں کی خدمت
کریں.دوسروں سے خدمت لینے میں تو وہ ایک گونہ عار محسوس کرتے.حضرت عوف بن مالک النجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک موقع
پر ہم سات، آٹھ یا نو افراد آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر تھے.ﷺ نے فرمایا کیا تم اللہ کے رسول کے ساتھ ایک عہد نہیں کرو گے؟ حضرت
عوف بیان کرتے ہیں کہ ہم نے کچھ ہی عرصہ قبل حضور ﷺ کے دست مبارک پر
بیعت کی تھی چنانچہ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ ! ہم تو پہلے ہی عہد کر چکے ہیں.اس پر
آنحضرت ﷺ نے اپنا سوال دو ہرایا اور ہم نے وہی جواب دیتے ہوئے عرض کیا
کہ اے اللہ کے رسول ! اب آپ ہم سے کون سا عہد لینا چاہتے ہیں؟ آپ
نے فرمایا یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے
اور یہ کہ تم پنجوقتہ فرض نمازیں ادا کرو گے اور اللہ کی اطاعت کرو گے اور کسی سے کچھ
نہیں مانگو گے.حضرت عوف بن مالک بیان فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے
دیکھا کہ ان اصحاب میں سے کسی سوار کے ہاتھ سے گھوڑے کا چابک بھی گر جاتا تو وہ
304
Page 317
کسی سے یہ بھی نہیں کہتا تھا کہ یہ چابک اٹھا کر مجھے دے دو.(صحیح مسلم - كتاب الزكاة - باب كراهة المسئلة للناس)
خدمت خلق پر جو اتنا زور دیا گیا ہے تو یہ کوئی محض خشک زاہدانہ تعلیم نہیں ہے بلکہ
انسانی رویوں میں لطافت اور شائستگی پیدا کرنے کی ایک کوشش ہے تا کہ اس میں
اعلیٰ اقدار کا ذوق پروان چڑھے.اگر ایک بار اس قسم کا اعلیٰ ذوق پیدا کر دیا جائے تو
بآسانی یہ تربیت بھی کی جاسکتی ہے کہ انسان خدمت ہی میں لذت محسوس کرنے لگے
بجائے اس کے کہ وہ دوسروں کے احسانات اور رحم وکرم کا منتظر رہے.مخلوق خدا کی خدمت نصف ایمان ہے.اسلام کا موقف بھی یہی ہے کہ نیکی
بجائے خود ایک انعام ہے اور یہ ایک ایسی بات ہے جو منطق اور دلائل سے بالا ہے.اسے صرف محسوس کیا جا سکتا ہے.رضائے باری تعالیٰ کا حصول
اسلام انسانی کردار میں محض اعلیٰ اقدار پیدا کرنے پر اکتفا نہیں کرتا بلکہ یہ شعور
بھی پیدا کرتا ہے کہ اصل اہمیت اس بات کو حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کسی
شخص کی نیکیوں کی قدر و منزلت کیا ہے.اس امر پر زور دینے سے اس انسانی خواہش
کا بھی سد باب ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے انسان چاہتا ہے کہ لوگ اس کی نیکیوں کو
سرا ہیں لیکن ایک حقیقی مومن کے لئے تو اتنا یقین ہی کافی ہے کہ اس کے اچھے اور
بُرے تمام اعمال خبیر اور بصیر خدا کی نظر میں ہیں.چنانچہ قرآن کریم فرماتا ہے.يَوْمَئِذٍ تُحَدِّتْ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا هِ يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا
لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ
شَرَّايَرَه
305
(سورۃ الزلزال آیات ۵ تا ۹)
Page 318
ترجمہ:.اس دن وہ اپنی خبریں بیان کرے گی کیونکہ تیرے رب نے
اسے وحی کی ہوگی.اس دن لوگ پراگندہ حال نکل کھڑے ہوں گے
تا کہ انہیں ان کے اعمال دکھا دیئے جائیں.پس جو کوئی ذرہ بھر بھی نیکی
کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا اور جو کوئی ذرہ بھر بھی بدی کرے گا وہ اسے
دیکھ لے گا.یہ کہنا بے جا نہ ہو گا کہ یہ تعلیم اصلاح معاشرہ کی طرف ایک اہم قدم ہے اور
نمود و نمائش اور فخر و مباحات کا واحد اور مؤثر علاج بھی یہی ہے.صدقہ و خیرات کے وسیع تر معنوں میں آنحضرت ﷺ نے مندرجہ ذیل
اعمال کو ایسی نیکیوں میں شامل فرمایا ہے جن کا اجر خود اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے.حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ انسانی اعضاء
میں سے ہر عضو کا ہر روز صدقہ دینا واجب ہے.دو افراد کے مابین انصاف کرنا
صدقہ ہے.کسی شخص کو سوار ہونے میں یا اس کا سامان چڑھانے میں مدد دینا بھی
صدقہ ہے.راستہ میں سے کسی تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا بھی صدقہ ہے.(بخاری ومسلم )
عدی بن حاتم روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا اگر کوئی
مسلمان درخت لگاتا ہے اور پھر اس میں سے جو کچھ کھایا جاتا ہے وہ درخت لگانے
والے کی طرف سے صدقہ ہے.اور اگر اس میں سے کچھ چوری کر لیا جاتا ہے یا اس
ย
میں سے لے لیا جاتا ہے تو وہ بھی صدقہ ہے.(صحيح البخارى كتاب المزارعة باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه)
ابن ابی حاتم " روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا آگ سے بچو
خواہ آدھی کھجور صدقہ میں دے کر.اور اگر اس کی طاقت نہیں رکھتے تو اچھی بات کہہ
(صحيح البخارى كتاب الادب باب طيب الكلام
306
Page 319
حضرت ابو موسیٰ اشعری روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا اگر
ایک شخص کے پاس کچھ نہیں ہے تو اسے چاہئے کہ اپنے ہاتھوں سے کام کرے اور اپنی
کمائی میں سے کچھ خیرات بھی دے.اگر وہ کام نہیں کر سکتا تو وہ کسی ضرورت مند
بے بس کی مدد کرے.اگر وہ یہ بھی نہیں کر سکتا تو اسے چاہئے کہ دوسروں کو نیکی کی
ترغیب دے.اور اگر وہ اس کی طاقت بھی نہیں رکھتا تو اسے چاہئے کہ وہ بدی کے
ارتکاب سے بچتا رہے.یہ بھی صدقہ ہے.(صحیح البخارى كتاب الزكاة - باب : على كل مسلم صدقة فمن لم يجد فليعمل بالمعروف )
ایک اور حدیث میں آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا
اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا باعث ہے.لوگوں کے دکھ درد سے ہمیشہ باخبر رہنا
اسلام دوسروں کے دکھ درد کا شعور اور احساس پیدا کرتا ہے.چونکہ یہ پہلو قبل ازیں
سماجی، اقتصادی اور سیاسی امن کے ضمن میں زیر بحث آچکا ہے اس لئے یہاں اس پر مزید
کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے.محبت و شفقت کا وسیع دائرہ
اسلام انسانی محبت اور محبت کی اس صلاحیت کو صرف بنی نوع انسان تک محدود
نہیں رکھتا بلکہ اسے ساری مخلوق خدا تک پھیلا دیتا ہے.اس کا دعویٰ ہے کہ یہ وہ
آخری مذہب ہے جو کسی ایک قوم کے لئے نہیں بلکہ تمام انسانیت کے لئے نازل ہوا
ہے.عام طور پر یہی توقع کی جاتی ہے کہ آنحضرت ﷺ کی ذات بابرکات کو تمام
307
Page 320
بنی نوع انسان کے لئے نور اور رحمت کا منبع قرار دیا جائے گا.لیکن آدمی یہ دیکھ کر
صلى الله
حیران رہ جاتا ہے کہ قرآن کریم آنحضرت ﷺ کو رَحْمَةٌ لِّلْعَلَمِينَ قرار دیتا ہے
صلى الله
یعنی آپ نہ صرف بنی نوع انسان بلکہ تمام جہانوں کے لئے رحمت ہیں
(سورۃ الانبیاء آیت (۱۰۹.عربی میں عالم کے معنی ایک جہان یا سارے جہان کے
ہوتے ہیں لیکن یہاں العالمین کا لفظ استعمال ہوا ہے جو عالم کی جمع ہے.اس لحاظ
سے یہاں اس لفظ سے مراد ایک جہان نہیں بلکہ تمام جہان ہیں.ممکن ہے ایک
متشکلک اتنے بڑے دعوی کی صداقت کا قائل نہ ہو سکے لیکن اگر مقام نبوت کی آفاقیت
جو آنحضرت ﷺ کی ذات بابرکات میں بدرجہ اتم پائی جاتی ہے، کا گہرا عرفان نصیب
ہو جائے تو انسان پر رَحْمَة للعلمین کے مقام و مرتبہ کی عظمت کھل جاتی ہے.تخلیق انسانی کا مقصد
قرآن کریم کے نظریہ کے مطابق اگر یہ کائنات محض بے جان اور بے شعور
مخلوقات پر مشتمل ہوتی تو تخلیق کائنات کا فعل ہی نعوذ باللہ عبث اور لغو ٹھہرتا.اس کی
وجہ یہ ہے کہ اگر ایک باشعور مخلوق نہ ہوتی تو خالق کا عرفان کسے نصیب ہوتا.تخلیق کا ئنات کا مقصد دراصل ایک ایسے شعور کی تخلیق تھا جسے رفتہ رفتہ ترقی اور
وسعت دے کر ایک اعلیٰ مقام تک پہنچانا تھا تا کہ تخلیق کا اصل مقصد حاصل کیا
جاسکے.ظاہر ہے کہ یہ کوئی معمولی مقصد نہیں ہے.اس کی پوری وضاحت ایک الگ
تفصیلی بحث کی محتاج ہے جس کی آج کے خطاب میں گنجائش نہیں ہے البتہ آسان
لفظوں میں مختصر یوں کہہ سکتے ہیں کہ تخلیق کائنات کی علت غائی ایک اعلیٰ درجہ کی
باشعور ہستی کی پیدائش ہی تھی جو نہ صرف اپنی مرضی سے اللہ تعالیٰ کے حسنِ کامل کے
308
Page 321
سامنے جو تمام کا ئنات میں جلوہ گر ہے سرتسلیم خم کرے بلکہ بنی نوع انسان کی اس حقیقی
مقصد کی طرف راہنمائی بھی کرے یا کم از کم ان لوگوں کے لئے اس راہ پر چلنا ممکن
بنا دے جو واقعی اللہ تعالیٰ کی اتباع کرنا چاہتے ہیں.اگر کچھ دیر کے لئے فرض کر لیا
جائے کہ تخلیق کائنات کا کوئی مقصد نہیں تو اسی لمحہ پیدائش کا ئنات کا جواز ہی ختم ہو
جاتا ہے.اس حقیقت کو سمجھنے کے لئے ایک سادہ سی مثال دی جا سکتی ہے.ایک
پھل دار درخت لگانے ، اس کی آبیاری، دیکھ بھال اور تراش خراش کا مقصد اس
درخت کا پھل ہی تو ہے.اگر پھل نہ ہو تو درخت بھی نہ ہو.اگر مقصد کا حصول نہ ہو تو
پودا لگانے اور اس کی دیکھ بھال اور پرورش کی تمام تر کوششیں فضول اور بے معنی ہو کر
رہ جاتی ہیں.اس لحاظ سے درخت کا وجود جس میں جڑیں، تنا، شاخیں، پتے اور
کونپلیں سب شامل ہیں پھل ہی کا مرہون منت ہے.اس حقیقت کے باوجود کہ
درخت کے یہ سب حصے پھل سے پہلے وجود میں آئے پھر بھی یہ درخت کی علت غائی
یعنی پھل ہی کے ممنون ہیں.یہ علت غائی اور مقصد ہی کا فیض ہے جس کی وجہ سے
تخلیق کا عمل جاری و ساری ہے.تخلیق کے اس مقصد و منتهی یعنی انسان اور باقی
کائنات کے باہمی تعلق کی روشنی میں اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کیا جائے تو یہ معلوم کر
کے حیرت ہوتی ہے کہ اسلام صرف اللہ تعالیٰ اور انسان کے تعلق ہی کا احاطہ نہیں کرتا
بلکہ انسان کے حیوانات اور جمادات سے تعلق پر بھی محیط ہے.اس نقطہ نگاہ سے کائنات
کی ہر چیز مقدس بن جاتی ہے اس لئے نہیں کہ وہ انسان سے اعلیٰ ہے بلکہ اس لئے کہ
خالق کا ئنات نے خاص طور پر اسے براہ راست یا بالواسطہ انسان کے لئے پیدا کیا
ہے.اس لحاظ سے کائنات میں کوئی شے بھی فضول، بے معنی اور الگ تھلگ نہیں
رہتی.حتی کہ کرہ ارض سے بعید ترین فاصلوں پر واقع ستاروں کا وجود بھی بامعنی اور
با مقصد ہو جاتا ہے اور تخلیق کے منصوبہ میں ان کا مقام واضح ہو جاتا ہے.309
Page 322
یہی وہ نکتہ ہے جسے قرآن کریم نے بار بار مختلف زاویوں سے بیان کیا ہے جس
کی چند مثالیں درج ذیل ہیں.وَالشَّمْسِ وَضُحَهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلْهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلْهَا ۖ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَهَا
وَالسَّمَاءِ وَمَابَنْهاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا طَعْهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوْهَا فَالْهَمَهَا فُجُورَهَا
وَتَقُوهَا قَدْأَفْلَحَ مَنْ زَكَهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَهَا (سورة الشمس آیات ۲ تا ۱۱)
ترجمہ: قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی.اور چاند کی جب وہ
اس کے پیچھے آئے.اور دن کی جب وہ اس (یعنی سورج) کو خوب
روشن کر دے.اور رات کی جب وہ اسے ڈھانپ لے اور آسمان کی
اور جیسے اُس نے اُسے بنایا.اور زمین کی اور جیسے اُس نے اُسے بچھایا.اور ہر جان کی اور جیسے اس نے اسے ٹھیک ٹھاک کیا.پس اس کی
بے اعتدالیوں اور اسکی پر ہیز گاریوں ( کی تمیز کرنے کی صلاحیت) کو
اس کی فطرت میں ودیعت کیا.یقیناً وہ کامیاب ہو گیا جس نے اس
تقویٰ) کو پروان چڑھایا.اور نامراد ہو گیا جس نے اسے مٹی میں گاڑ
دیا.یک
وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَتِ
لقَومٍ يَتَفَكَّرُونَ
( سورة الجاثیہ آیت (۱۴)
ترجمہ:.اور جو بھی آسمانوں میں اور زمین میں ہے اس میں سے سب
اس نے تمہارے لئے مسخر کر دیا.اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لئے
یقیناً کھلے کھلے نشانات ہیں.أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِى السَّمواتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُم
نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى
ولا كتب سيره
(سورۃ لقمان آیت ۲۱)
310
Page 323
ترجمہ:.کیا تم نے غور نہیں کیا کہ اللہ نے تمہارے لئے مسخر کر دیا ہے جو
بھی آسمانوں اور زمین میں ہے اور اس نے اپنی نعمتیں تم پر ظاہری طور پر
بھی پوری کیں اور باطنی طور پر بھی.اور انسانوں میں سے ایسے بھی ہیں
جو اللہ کے بارہ میں بغیر کسی علم یا ہدایت یا روشن کتاب کے جھگڑتے
ہیں.لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقويم (سورۃ التین آیت ۵)
ترجمہ :.یقیناً ہم نے انسان کو بہترین ارتقائی حالت میں پیدا کیا.قرآن کریم کی بہت سی دیگر آیات یہاں تک کہ بعض چھوٹی سورتیں بھی سب کی
سب اسی مضمون کے لئے وقف ہیں.ان سے پتہ چلتا ہے کہ انسان ایک عالم صغیر
ہے جس پر تمام مخلوقات نے اپنے اثرات مرتب کیے ہیں یہاں تک کہ بعید ترین
ستاروں نے بھی اس عالم صغیر یعنی انسان پر اپنے اثرات ڈالے ہیں مگر انسان اور
باقی کائنات کے مابین یہ تعلق غلام اور آقا کا نہیں بلکہ آقا اور غلام کا ہے.آقا اپنے
ان غلاموں کے آگے سر نہیں جھکاتے بلکہ غلام ان کی خدمت میں کمر بستہ رہتے ہیں.پس انسان اس ساری کائنات کا آتا ہے لیکن غلام ہے صرف اس ذات کا جو اس
ساری کائنات کی خالق و مالک ہے.اب دیکھئے کہ اسلام کا یہ فلسفہ دیگر کئی مذاہب
کے فلسفوں سے کس قدر مختلف ہے جو صرف بتوں کی عبادت ہی نہیں سکھاتے بلکہ نیچر
کی عبادت کی کئی شکلیں بھی ان میں پائی جاتی ہیں.ان مذاہب کی تعلیمات کے
مطابق تو یوں لگتا ہے جیسے سورج ، چاند، ستارے، درخت ، بجلی ، طوفان، سمندر یہاں
تک کہ گائے، سانپ اور پرندے ایک پہلو سے انسان سے بھی اعلیٰ مقام اور مرتبے
پر فائز ہیں.انسان کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ وہ ان چیزوں کو معبود تسلیم کر کے ان کی
عبادت کرے کیونکہ بقول ان کے ان سب کو انسان پر ایک قسم کی فضیلت حاصل
311
Page 324
ہے.مختصر یہ کہ انسان کو مخلوقات میں سب سے نچلے درجہ کی مخلوق قرار دے کر اسے
ہر اُس چیز کا مطیع اور خادم بنا دیا جاتا ہے جو محض اس کی خدمت کے لئے پیدا کی گئی
تھی.نظام کائنات کا جو عرفان اسلام نے عطا فرمایا ہے اس کے مطابق انسان مخدوم
ہے اور باقی ساری کائنات اس کی خادم ہے اس لحاظ سے ساری کائنات میں انسان
ہی اپنے خالق کے احسانات کا سب سے بڑھ کر مورد ہے.پس اسے سب سے زیادہ
خدا تعالیٰ کا شکر گزار اور احسان مند بھی ہونا چاہیئے جس کی خدمت کے لئے اللہ تعالیٰ
نے تمام کائنات کو مسخر کر دیا ہے.بالفاظ دیگر اللہ تعالیٰ کی غلامی میں آ کر انسان ہر
دوسری غلامی سے رہائی پالیتا ہے.انسان ساری کائنات کے شعور اور ضمیر کی علامت
اور اس کی تجسیم ہے.جب انسان خالق کے سامنے سر بسجود ہوتا ہے تو گویا
ساری کائنات خالق کے حضور سجدہ ریز ہو جاتی ہے اور جب انسان اپنے خالق کی
طرف رجوع کرتا ہے تو گویا کل کائنات اپنے خالق کی طرف لوٹتی ہے.اسلام کے
نزد یک اسی مقصد کے حصول اور اس کے مطابق انسانی زندگی کو ڈھالنے میں حقیقی اور
کامل امن پوشیدہ ہے.اس سارے فلسفہ کو قرآن کریم کی اس آیت میں جسے مسلمان
بکثرت دوہراتے رہتے ہیں نہایت اختصار کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے:
1.....إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعونَ
(سورۃ البقرۃ آیت ۱۵۷)
ترجمہ :.ہم یقینا اللہ ہی کے ہیں اور ہم یقیناً اسی کی طرف لوٹ کر جانے
والے ہیں.بہت کم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں لوٹنے سے جسمانی طور پر نہیں بلکہ روحانی طور
پر لوٹنا مراد ہے اور یہ آیت صرف امر واقعہ کو بیان نہیں کرتی بلکہ انسان کو اس کا
مقصد حیات بھی یاد دلاتی ہے.جیسے Salmon مچھلی کو اس وقت تک چین نہیں آتا
312
Page 325
جب تک کہ وہ ان سمندروں کی طرف واپس نہ لوٹ جائے جہاں اس نے جنم لیا تھا
بالکل ایسے ہی انسان کا دل کبھی اطمینان نہیں پا سکتا تا وقتیکہ وہ روحانی طور پر اپنی
پیدائش کے منبع و ماخذ تک نہ لوٹ جائے.مندرجہ ذیل آیت کے یہی معنی ہیں:
الَّذِينَ امَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بذِكْرِ اللهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ
(سورۃ الرعد آیت ۲۹)
ترجمہ :.وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن
ہو جاتے ہیں.سنو! اللہ ہی کے ذکر سے دل اطمینان پکڑتے ہیں.اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کوئی امن نصیب نہیں ہو سکتا
اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کوئی امن نصیب نہیں ہوسکتا یہی وہ راز ہے جس کو جانے بغیر
نہ تو انسان کو اطمینان قلب نصیب ہو سکتا ہے اور نہ ہی معاشرہ میں امن وسکون کی
ضمانت دی جا سکتی ہے حقیقی امن اور اطمینان تک لے جانے والا اور کوئی راستہ نہیں
ہے.اللہ تعالیٰ کی محبت ہی ہے جس کے نتیجہ میں اس کی مخلوق کا سچا احترام دل میں
پیدا ہوسکتا ہے.مخلوق جس قدر اعلیٰ درجہ کی ہوگی اسی قدر وہ خالق کے قریب تر ہو گی
اور اس کا تعلق اپنے خالق سے اتنا ہی مضبوط تر ہو گا.انسان ایک عظیم تر اور
اعلی تر مقصد کے ساتھ دوسرے انسانوں کا احترام کرنا شروع کر دیتا ہے یعنی اپنے
خالق کے احترام کی وجہ سے اس پر جو فرض عائد ہوتا ہے اس کے باعث وہ انسانیت
کا احترام کرنا شروع کر دیتا ہے.خلاصہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے
جو اس کی مخلوق کی محبت میں تبدیل ہو جاتی ہے.اگر درمیان سے اللہ تعالیٰ کی محبت
نکال دی جائے تو دفعتاً انسانی تعلقات کا سارا منظر ہی بدل جاتا ہے.اللہ تعالیٰ کے
313
Page 326
نہ ہونے سے جو خلا پیدا ہو گا اسے پُر کرنے کے لئے فوراً انسان کی انا سامنے آ جائے
گی یہ ایک نادانی کی بات اور بے حد جاہلانہ فلسفہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے بغیر رہ
سکتا ہے.بالآخر دہریت کا نتیجہ صرف یہی نہیں نکلتا کہ بقول شخصے خدا مر جاتا ہے بلکہ اس
کے نتیجہ میں اچانک ہزارہا جھوٹے خدا زندہ ہو جاتے ہیں.ہر وہ ذات جو شعور رکھتی
ہے آن واحد میں اپنے زعم میں خدا بن جاتی ہے.آنا اور انتہا درجہ کی خود غرضی طاقت
پکڑ لیتی ہے اور اس کی حکمرانی ہو جاتی ہے.ایسے افراد پر مشتمل معاشرہ بھی ہمیشہ
انا پرست اور خود غرض رہتا ہے بے لوث ہو کر دوسروں کیلئے نفع رساں بنے کی کوئی
منطق ہی باقی نہیں رہتی.ایک رحیم و کریم خدا کی شکل میں کوئی بیرونی حوالہ ہی باقی
نہیں رہتا جو تمام انواع کی مخلوقات کو باہم متحد رکھنے اور یکجا کرنے کا واحد ذریعہ ہے.اس سے بڑھ کر اسلام کا کوئی اور فلسفہ نہیں ہے.اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کئے
بغیر کوئی فرد حقیقی اطمینان حاصل نہیں کر سکتا اور حقیقی اطمینان کے بغیر معاشرہ
امن و آشتی کا گہوارہ نہیں بن سکتا.قیام امن کے لئے تمام ایسی کوششیں جن کا محرک
ذاتی اغراض ہوں یقیناً نا کام اور بے نتیجہ رہتی ہیں.اگر اللہ تعالیٰ موجود نہیں تو پھر
امن بھی نہیں اور اس حقیقت کا شعور ہی دراصل دانائی کا کمال ہے.314