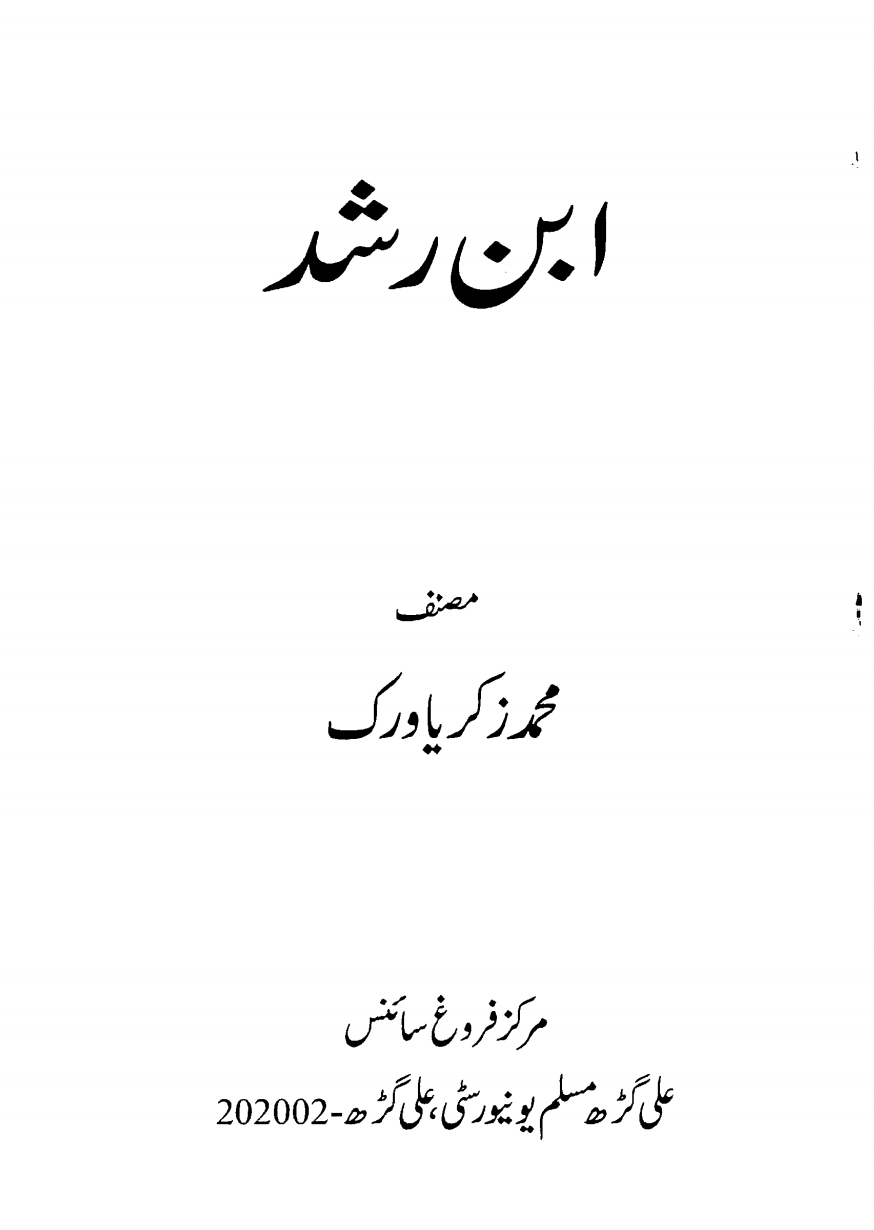Complete Text of Ibn-eRushd
Content sourced fromAlislam.org
Page 1
1
ابن رشد
صنف
محمد زکر یا ورک
مرکز فروغ سائنس
علی گڑھ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ - 202002.
Page 2
نام کتاب
مصنف
ایڈیٹر
اشاعت اول
ابن رشد
محمد زکریا ورک ،کنگسٹن، کینیڈا
پروفیسر حکیم سید ظل الرحمن
فروری 2007ء
تعداد
700 پیپر بیک
300 ہارڈ باؤنڈ
قیمت
اشاعت نمبر
22
طباعت
ناشر
پچاس روپئے ( 50.RS) پیپر بیک
ساٹھ روپئے ( 60.RS) ہارڈ باؤنڈ
لیتھو انسیٹ پر نٹس کا چل حال علی گڑھ
مرکز فروغ سائنس
علی گڑھ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ - 202002
1
Page 3
Naseem Ahmad
VICE-CHANCELLOR
ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY
ALIGARH-202002
پیش لفظ
یہ مسرت کی بات ہے کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا مرکز فروغ سائنس بانی درس گاہ سرسید احمد خان کے تعلیمی مشن کو آگے
بڑھانے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے.سرسید نے سائنس کے علوم کی توسیع و ترقی پر سب سے زیادہ توجہ دی.ان کی یہ کوشش تھی کہ
مسلمانوں میں سائنسی مزاج پیدا ہو.انہوں نے اپنی تعلیمی تحریک کو پروان چڑھانے کے لئے سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی اور بڑی تعداد
میں انگریزی کتابوں کا اردو میں ترجمہ کرایا.مسلمانوں کی تعلیمی ترقی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے مقصد ومنہاج کا بنیادی کلیہ ہے.دور حاضر میں یہ ترقی عصری علوم کے
حصول کے بغیر ناممکن ہے.چونکہ مسلمان طلبا کی کثیر تعداد دینی مدارس میں زیر تعلیم ہے اس لئے میں کجھتا ہوں کہ ان
کو جدید تعلیمی نظام
سے منسلک کئے بغیر اس مقصد کا حصول مشکل ہے.مجھے خوشی ہے کہ یو نیورسٹی کا مرکز فروغ سائنس اس سمت میں بامعنی اور نتیجہ خیز
سرگرمیوں میں مصروف ہے.انشا اللہ دینی مدارس میں سائنس کو رواج دینے کی ان سرگرمیوں کے بہتر اور زود اثر نتائج برآمد ہوں گے.مرکز فروغ سائنس نے دینی مدارس کے ساتھ مسلم زیر انتظام تعلیمی اداروں کو عام فہم اور دو زبان میں سائنس کا درسی مواد
فراہم کرنے کی ذمہ داری بھی قبول کی ہے.اب تک اس کی کئی کتا بیں منظر عام پر آچکی ہیں.ان میں بعض انگریزی کتابوں کے
ترجمے بھی شامل ہیں.اس سال بھی تقریبا سات کتابیں طباعت کے آخری مرحلے میں ہیں.به تاریخی حقیقت ہے کہ مسلمان اپنے تہذی پر تھا کے ابتدائی دور میں قائل یہ علم کے سالار تھے.مختلف سائنسی علوم کے فروغ میں
ان کا زبردست حصہ ہے، در حقیقت کئی معنوں میں دو ان علوم کے پانی قرار دئے جاسکتے ہیں.محمد ذکر یا درک کی تصنیف ” این رشد"
مسلمانوں کی ہی متروکہ روایت کی بازیافت کی کوشش ہے.دینی مدارس کے طلبا اور دیگر اردو داں عوام کو اس تصنیف سے نئی تحریک ملے گی.مجھے یقین ہے کہ مرکز فروغ سائنس کے اس اشاعتی سلسلے کی پذیرائی ہوگی اور اردو زبان کے حوالے سے مسلم طبقہ عصر حاضر
کے تقاضوں کو محسوس کرے گا.میں مرکز فردریغ سائنس کی ان کاوشوں
کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں.قسم أحمد
سیم احمد )
وائس چانسلر لاج
می گردہ مسلم یونیورسٹی پہلی گره
22 فروری 2007،
Phone: (0) (0571) 2700994, (R) (0571) 2700173, Fax (0) (0571) 2702607, (R) (0571) 2700087, Email : veamu@sancharnet.in
Page 4
ابتدائیہ
مرکز فروغ سائنس کے قیام کے بعد سے ہی اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ مسلم اداروں، بالخصوص
دینی مدارس میں سائنس کو فروغ دینے میں اُردو میں لکھی ہوئی سائنس کی کتا میں بہت کارآمد ثابت ہوں گی.اگر یہ
کتا ہیں عام نہم زبان میں ہوں اور یہ آسمانی فراہم ہو سکیں تو نہ صرف طلبہ بلکہ دیگر اردو جانے والوں کے لئے بھی مفید
ثابت ہوں گی.مرکز کے تعلیمی پروگراموں میں شریک ہونے والے ملک کے مختلف علاقوں سے بیشتر افراد بالخصوص
مدارس کے اساتذہ نے بھی اس بات کی طرف نہ صرف توجہ دلائی بلکہ بار بار یہ فرمائش بھی کی کہ مرکز فروغ سائنس
جدید علوم کو اُردو زبان میں پیش کرنے کا بیڑا اٹھائے.لیکن بعض نامساعد حالات کہ وجہ سے مرکز اس کام میں کوئی
خاطر خواہ پیش رفت نہ کر سکا.علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے سابق وائس چانسلر جناب محمد حامد انصاری صاحب نے اس سلسلے میں حوصلہ
افزائی کی اور ہر قدم پر مدد کی.اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اردو میں سائنسی تعلیم کا مواد تیار کرنے کے منصوبے کو عملی جامہ
پہنانے کی شروعات ہوسکی.اس کے تحت مرکز نے مندرجہ ذیل اقسام کی کتابوں
کو لکھوانے اور ان کی اشاعت کا ایک
پروگرام بنایا.ابتدائی سائنس کی نصابی اور اضافی کتابیں جو دینی مدارس اور اُردو میڈیم اسکولوں میں استعمال کی جاسکیں.جدید سائنسی موضوعات پر عوام کے لئے عام فہم زبان میں کتا ہیں.معیاری کتابوں اور مضامین کے اردو تراجم اور تشخیص.اساتذہ کے لئے سائنس پڑھانے میں معاون کتابیں.سائنس دانوں کے مختصر حالات زندگی اور کام پر مبنی کتا ہیں.مرکز کے اشائی پروگرام کی پہلی کتاب تھے سائنس داں " جنوری ۲۰۰۲ء میں شائع ہوئی.اس
منصوبے میں سائنس
کی ڈکشنری اور مسلمان سائنس دانوں کے کارناموں پر کتابوں کی ایک سیر یز بھی حال ہی میں
شامل کی گئی ہے.موجودہ وائس چانسلر جناب نسیم احمد صاحب نے نہ صرف ہمت افزائی اور مدد جاری رکھی بلکہ ذاتی دلچپسی
بھی لی جس سے یہ سلسلہ نہ صرف قائم ہے بلکہ ترقی کی راہ پر گامزن ہے.مرکز کی سرگرمیوں میں ان کی ذاتی دلچسپی اور
Page 5
تعاون کا شکر یہ ادا کرنا نا کافی اور رکھی ہو گا.میں نسیم صاحب کا تہ دل سے ممنون ہوں.کچھ عرصہ قبل دینی مدارس کے چند اساتذہ نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ مرکز کے اشاعتی پروگرام میں
جدید سائنس علوم پر کتابوں کے علاوہ سائنس کے میدان میں اسلاف کے کارناموں پر بھی کتابوں کی اشاعت
ضروری ہے.سائنس کی تاریخ میں مسلمانوں کا بڑا حصہ ہے، خصوصاً عہد وسطی میں مسلمان سائنس دانوں کے
کارنامے ہی جدید سائنس کی اساس ہیں.اس لئے ان کا تعارف بھی سائنس میں دلچسپی اور فروغ کے لئے ضروری
ہے.نیز ان معلومات سے دینی مدارس میں جدید سائنس کی تعلیم کو داخلِ نصاب کرنے کی تحریک بھی ملے گی.زیر نظر کتاب مرکز کے اشاعتی سلسلے کی بائیسویں کتاب ہے.سائنس میں مسلمانوں کے حصے کا مجموعی
جائزہ اس سے قبل مرکز کی اشاعت مسلمانوں کے سائنسی کارنامے میں پیش کیا جا چکا ہے.محمد زکریا ورک
صاحب نے اس کتاب میں اپنے وسیع مطالعے اور کثرت معلومات کا مظاہرہ نہایت خوش اسلوبی سے کیا ہے.ان کی
اس صلاحیت سے مزید فائدہ اٹھانے کے لئے ہم نے ان سے درخواست کی تھی کہ وہ اب منفر د مسلمان سائنس دانوں
پر بھی کتاب تحریر کریں.زیر نظر کتاب میں انہوں نے مسلمانوں کے عہد میں اسپین کے عظیم سائنس داں اور فلسفی ابن
رشد کے کارناموں کا نہایت جامع انداز میں احاطہ کیا ہے.اس کتاب کی تصنیف کے لئے ان کا بے حد مشکور ہوں.مجھے قوی امید ہے کہ اس کتاب کی اشاعت سے نہ صرف سائنس کو مدارس میں عام کرنے کی مرکز کی کوششیں کارآمد
ہوں گی بلکہ اس موضوع پر تحقیق کرنے والوں کے لئے بھی یہ کتاب معلومات کا ایک گراں بہا ذریعہ ثابت ہوگی.پروفیسر سید ظل الرحمن صاحب، صدر ابن سینا اکیڈمی کا میں ممنون ہوں کہ انہوں نے اپنی بے پناہ
مصروفیت کے باوجود بڑی محنت سے اس کتاب کی ادارت کا مشکل کام انجام دیا ہے.جس سے کتاب میں مزید نکھار
آگیا ہے.میں اللہ تعالٰی سے دعا کرتا ہوں کہ جس خلوص نیتی سے جن مقاصد کے لئے یہ کام کیا جا رہا ہے، اس
میں کامیابی ہو، آمین !
ڈاکٹر شاہد فاروق
ڈائرکٹر، مرکز فروغ سائنس
جنوری ۲۰۰۷
Page 6
پیش لفظ
میر لیے یہ بات نہایت فخر و انبساط کا باعث ہے کہ قریب پچاس سال بعد مرکز فروغ
سائنس علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے زیر اہتمام عالم اسلام کی قد آور شخصیت ابن رشد القرطبی کی زندگی
اور کارناموں پر کتاب شائع کی جارہی ہے.محمد ابن رشد اسلامی اسپین کے سب سے عظیم فقیہ، فلاسفر، طبیب، ماہر فلکیات، قانون
گو، قاضی ، مصنف اور ارسطو کی کتابوں کے شرح نگار تھے.اسلامی دنیا میں آپ کی شہرت بطور فقیہ
اور یورپ میں بطور فلاسفر کے ہے.بارہویں صدی سے لے کر سولہویں صدی تک یورپ میں آپ
کا طوطی بولتا رہا.آپ کے سیاسی ، سماجی ، علمی و فلسفیانہ نظریات سے اہلِ یہود اور اہلِ نصاری نے
بہت استفادہ کیا جس سے نشاۃ ثانیہ ممکن ہوئی.یورپ کی علمی ، سائنسی اور مادی ترقی دراصل آپ کی
ارسطو کی شرح کردہ کتابوں کی رہین منت ہے.ابن رشد نہ صرف عالم اسلام بلکہ یورپ کے بھی قد آور فلاسفر تھے کیونکہ انہوں نے
ارسطو جیسے عالم بے بدل کو یورپ میں روشناس کرایا تھا.عالم اسلام میں ان کی قدر کی وجہ ان کا رتبہ
جہاد ہے.جس رنگ میں انہوں نے عقل اور مذہب کے درمیان مطابقت پیدا کرنے کی کامیاب
سعی کی اس کے باعث ان
کو مجتہد اعظم کا لقب بہت زیب دیتا ہے.انگریزی زبان میں ابن رشد کی سواغ پر کتابیں محدود چند ہیں جبکہ فرانسیسی زبان میں
ارنسٹ رینان کی کتاب کے 1852ء میں منصہ شہود پر آنے کے بعد بہت سارا لٹریچر نمودار
ہوا.اردو زبان میں بھی آپ کی سوانح پر کتابوں کو ہاتھ کی انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے.اس کتاب میں
آپ کی سوانح کو سات حصوں میں تقسیم کر کے آپ کی زندگی کے چھپے ہوئے گوشوں
کو حتی الامکان
سامنے لانے کی کوشش کی گئی ہے.کتاب میں تمام انگریزی اقتباسات کا اردو میں ترجمہ میں نے کیا
Page 7
ہے اور کسی قسم کی کمی و بیشی کا میں ہی ذمے دار ہوں.اس کتاب کی تدوین اور تالیف میں جن احباب نے میری مدد اور حوصلہ افزائی فرمائی اگر
ان کا ذکر نہ کیا جائے تو یہ از حد نا شکر گزاری ہوگی.میں پروفیسر سید ابوالہاشم رضوی، ڈاکٹر شاہد
فاروق، پروفیسر حکیم سید ظل الرحمن، پروفیسر محمد بایومی (کوئنز یونیورسٹی کنگسٹن ) ، بشری ورک کے
ناموں کا خاص طور پر ذکر کرنا چاہتا ہوں.میں اس کتاب کو برادران ڈاکٹر محمد الحق ورک اور چودھری محمد ادریس ورک کے نام
معنون کرتا ہوں جن کے بے لوث پیار، دست شفقت ، سایہ عاطفت اور رہ نمائی نے مجھ میں
کتابوں کی محبت کا شعلہ اجاگر کیا.کنگسٹن کینیڈا
تمبر 2006
محمد زکریا ورک
zakariav@hotmail.com
Page 8
مقدمه
فلسفہ و حکمت میں مشرقی خلافت میں فارابی اور ابن سینا کو فضلیت کا جو مرتبہ حاصل ہے، مغربی خلافت
میں اسی بلند ترین منصب کا حامل اور اپنے لازوال کارناموں کی وجہ سے ہمیشہ زندور بنے والا نام ہے.اس
کا شمار اسلامی دنیا کے عظیم فلاسفہ میں کیا گیا ہے.دوسرے مسلمان فلاسفہ کے درمیان کا ایک امتیاز یہ ہے کہ وہ نہ صرف فلسفہ و حکمت اور طب
و سائنس کی ایک گرامی منزلت شخصیت ہے، بلکہ دینی علوم بالخصوص فقہ میں اپنی مہارت کی وجہ سے ممتاز دینی عالموں
کی صف میں شامل ہے، وہ حقیقی معنی میں جامع العلوم تھا.علوم عقلیہ اور علوم نقلیہ سے اپنے تعلق خاص ہی کی بناء پر
زندگی بھر ایک کشمکش میں مبتلا رہا.بلاد مشرق کے برخلاف مغرب کی اسلامی مملکت میں جس کا دارالخلافہ قرطبہ تھا، فلسفہ کی عام طور پر حوصلہ
افزائی اور سر پرستی نہیں کی گئی تھی.وہاں
فلسفہ کی تحصیل آسانی نہ تھی.مذہبیت کا اس قدر غلبہ تھا کہ بعض حکمرانوں کے عہد میں نہ صرف فلاسفہ کی کتابیں جلائی
گئیں بلکہ وہ خود مورد عتاب اور ستحق مز اقرار پائے.کو بھی اس آزمائش سے
گزرنا پڑا اور ذلت ورسوائی اور
قید و بند کی صعوبتیں اس کا مقدر بنیں.لیکن اس کے باوجود اندلس میں فلسفہ کا مطالعہ جاری رہا اور وہاں عمر بن یونس ، ابن حزم، ابن الکتانی،
محمد بن عبدون
جیلی ، ابوسلیمان محمد بن ظاہر سیستانی، ابوبکر احمد من جابر ، احمد بن حکم محمد ابن میمون ، ابن ماجه، این فیل، جیسے فلسفی پیدا ہوئے.مشرقی فلاسفہ فارابی ، کندی اور ابن سینا سے ابن باجہ، ابن طفیل اور کا درجہ کسی
طرح
کم نہیں ہے.این رشد بنیادی طور پر عقلیت پسند تھا اور نظام طبعی پر پورا یقین رکھتا تھا.لیکن وہ اسلامیات کا بھی ماہر تھا
اور فقیہ اور قاضی کی حیثیت سے اس کی شخصیت مسلمہ تھی.اس کی ذہنی مشکل کی بڑی وجہ یہی تھی کہ وہ مذہب اور فلسفہ کو
ساتھ لے کر چلنا چاہتا تھا اور انہیں ایک دوسرے کا مقابل نہیں سمجھتا تھا.مذہبی عقائد میں پختگی اور سائنس وفلسفہ سے
اپنے گہرے رشتہ کی وجہ سے اس نے مقدور بھر کلانی مباحث پر توجہ مبذول کی اور فلسفہ و مذہب کے درمیان اختلافی
مسائل میں تطبیق کی کوشش کی.اس کے نزدیک فلسفہ اور شریعت باہم متصادم نہیں ایک دوسرے کے ممد و معاون ہیں.(i)
Page 9
اس کی ذہنی و فکری رہ گزرا شاعر : سے مختلف تھی.ایک آزاد خیال مفکر ومدبر کی حیثیت سے اس نے جہاں فلسفہ و حکمت کے بعض مسائل میں قدما سے
اختلاف کیا وہاں فقہی مسائل میں مروجہ آرا سے وہ متفق نہیں رہا.آزادانہ غور و فکر کے بعد منشاء شریعت کو سمجھتے ہوئے اس
نے جو فیصلے صادر کئے ، وہ اس کی غیر معمولی ذہانت اور فقہی اجتہاد کا مظہر ہیں.عورت کی امامت کا مسئلہ موجودہ زمانے
میں ایک بہت اہم مسئلہ کے طور پر سامنے آیا ہے.علما کے درمیان اس پر بحث کا سلسلہ جاری ہے.موافقت و مخالفت
میں بہت سی باتیں کہی جارہی ہیں.لیکن یہ نیا مسئلہ نہیں ہے اور نہ آزادی نسواں کی موجودہ تحریک سے اس کا تعلق
ہے.صدر اول کے فقہا کے یہاں بھی یہ مسئلہ مختلف فیہ رہا ہے.نے پوری جرات سے عورت کی امامت کے
حق میں رائے دی.اس بارے میں مختلف آرا پیش کرتے ہوئے اپنی تائید میں اس نے ابوثور اور طبری کے حوالہ کے
ساتھ جمہور کے برخلاف فتوی دیا ہے کہ عورت علی الاطلاق عورتوں اور مردوں دونوں کی امامت کر سکتی ہے.بحیثیت
قاضی اور بحیثیت حاکم عورت کے تقرر کو بھی اس نے جائز قرار دیا ہے.اور موافق و مخالف رایوں کا تجزیہ کرتے ہوئے
کہا ہے کہ عورت قاضی ، حاکم اور فرمانروا مقرر ہو سکتی ہے.بغیر ولی عورت کے نکاح کے جواز و عدم جواز پر آج بھی بحث چھڑی ہوئی ہے.ابن شد نے ایک ہزار
برس پہلے کہا کہ بالغ ہو نے پر عورت کو جب مال میں تصرف کا شرعی حق حاصل ہے تو یہ نظیر اس بات کے لئے کافی ہے
کہ عورت
کو بغیر ولی کے نکاح کا حق بھی حاصل ہے.اس نے وراثت کے معاملہ میں قرآن کی واضح آیات کے سوا
دوسرے تمام معاملات میں عورتوں کے حقوق کو مردوں کے مساوی تسلیم کیا ہے.وہ جب قاضی القضاء کے منصب پر
فائز ہوا تو اس کی عمر صرف ۲۷ برس تھی، اس نے اس منصب کی پوری مدت میں کسی فقیہ یا قاضی کی تقلید کے بجائے خود
قرآن وسنت کی روشنی میں اجتہاد سے کام لیا.قرطبہ کی جامع مسجد کے امام ابن قران نے اس کے فتاوی کا ایک مجموعہ
مرتب کیا تھا جو پیرس کی نیشنل لائبریری میں محفوظ ہے.کو موطا امام مالک حفظ تھی.حافظہ کا یہ عالم تھا کہ
ابو تمام اور متنبتی کا دیوان بھی اسے حفظ یا تھا.اپنے فلسفیانہ نظریات میں ارسطو کا بڑی حد تک تابع تھا.اس نے ارسطو کے نظریات اور
اسلامی تعلیمات میں مطابقت کی کوشش کی.کا ئنات اور مادہ کی قدامت کا قائل تھا.اس کے نزدیک مادہ
از لی اور قدیم ہے اور اس کی بدلتی ہوئی صورتیں حادث ہیں.افلاک کو بھی وہ ازلی مانتا تھا.اس کے خیال میں خدا
اس کا خالق نہیں ہے.وہ صرف اس کی حرکت کو منظم کرتا ہے.وہ ارواح کو فانی تسلیم کرتا تھا اور قوم عاد کے وجود کا منکر
تھا.اس کے فلسفیانہ نظریات سے علماء کو اختلاف رہا.وہ اپنے استاد ابن باجہ کی طرح امام غزالی اور دوسرے علماء سے
مختلف یہ رائے رکھتا تھا کہ حقایق تک پہنچنے کے لئے علوم کشفیہ کی نہیں علوم نظریہ کی ضرورت ہے.مذہبی عقائد کے علاوہ عتاب شاہی کی ایک وجہ مشہور طبی مورخ ابن ابی اصیعہ نے دیکھی ہے کہ ابن
(ii)
Page 10
رشد نے حیوانات پر جو کتاب تحریر کی تھی اس میں جانوروں کی توصیف بیان کرتے ہوئے زرافہ کے ذکر میں لکھا تھا
کہ اسے اس نے شاہ بربر یعنی منصور کے یہاں دیکھا ہے.ظاہر ہے یہ صریحی طور پر باشاہ کے لئے تو ہین کا باعث
تھا.نے معذرت پیش کی کہ اس نے شاہ برین لکھا تھا، قاری نے غلطی سے اسے شاہ بر بر پڑھا.کا ایک بڑا کارنامہ تہافتہ انتہافتہ ہے.یہ کتاب امام غزالی کی تہافت الفلاسفہ کی تنقید میں لکھی
گئی تھی.امام غزالی نے اس کتاب میں فلسفہ اور فلاسفہ کی دھجیاں بکھیری ہیں.مسلمانوں میں سائنس اور فلسفہ کا جو
شوق پیدا ہو گیا تھا اور مسلمان علمی و سائنسی طور پر جس تیزی سے ترقی کر رہے تھے ، غزالی کی تعلیمات کے زیر اثر اس کو
بہت نقصان پہنچا اور وہ عقلی علوم سے دور ہوتے گئے.پہلا شخص ہے جس نے اس کے خلاف آواز اٹھائی
اور غزالی کے اثر کو زائل کرنے کی کوشش کی.سرسید نے بھی مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی دور کرنے اور انہیں جدید
سائنسی علوم سے آراستہ کرنے کی جب جدو جہد شروع کی تو انہیں بھی غزالی کی کتاب کا رد لکھنے کی ضرورت پیش آئی
اور انہوں نے انتظر فی بعض مسائل الامام الغزالی تصنیف کی.فقہ کے ساتھ ہیئت ، فلکیات اور طب میں کے اضافات کا ذکر ذکر یا ورک نے بہت تفصیل
سے کیا ہے.طب میں بعض دریافتوں کا سہرا کے سر ہے.مثلاً چیچک اور پر دو بھارت کے سلسلہ میں اس کے
بیانات قابل قدر اضافہ کی حیثیت رکھتے ہیں.جالینوس کی بیان کردہ بدن کی تیسری حالت "لا صحت ولا مرض" سے
وہ اتفاق نہیں کرتا ہے.اس کے نزدیک فعل تولید میں عورت کی منی کا کوئی دخل نہیں ہے.عورت بغیر انزال حاملہ
ہو جاتی ہے.اس نے لکھا ہے کہ اس سلسلہ میں جب مجھے ارسطو کا نظریہ معلوم ہوا تو میں نے اس کو محسوس کرنے کی
کوشش کی اور تجربہ سے یہ بات صحیح معلوم ہوئی.اس طرح اس نے اس رائج نظریہ کی تردید کی کہ مرد اور عورت دونوں
کی منی سے مل کر ایک تخلیق وجود میں آتی ہے.بعض مسائل میں اس نے جالینوس سے اختلاف کیا.مثلاً جالینوس متصلب دواؤں کو رطوبت کے ساتھ
مشروط کرتا تھا.نے کہا کہ مصلب دوائیں بارو ہوتی ہیں.صلابت اور جمود کا سبب برودت ہے نہ کہ
رطوبت - مرطب دوا میں سختی نہیں پیدا کر سکتیں.برودت کے ساتھ پیوست کی شرط لگائی جاتی ہے.کائی ، سدا بہار،
خرفہ، اسپغول کو اس نے بارہ ہونے کی وجہ سے مصلب قرار دیا ہے نہ کہ رطب ہونے کی وجہ سے.اس نے اب سے بہت پہلے تجربہ پرمینی بہت سی باتیں کتاب الکلیات میں درج کی ہیں مثلاً اس نے
لکھا ہے کہ جب دو قسم کی غذا میں ہوں ایک بھر بھری (غیر روغنی) اور دوسری لیسدار ( روغنی) تو قطعی طور پر بھر بھری کا
استحالہ جلد ہوگا.کیونکہ وہ حرارت سے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر جلد منفعل ہو جاتی ہے.بھر بھری غذا ئیں زود ہضم اور لیسدار
اور روغنی اشیاء دیر ہضم ہوتی ہیں.یا اس نے کہا کہ جالینوس اور اس کے متبعین نے ادویہ کے مزاج کو معلوم کرنے کے
ذرائع میں صرف رنگ بوذائقہ اور جلد استحالہ پر اکتفا کیا ہے.مثلاً ان کے نزدیک دوار حاروہ ہے جس کا مزہ تیز تلخ
(iii)
Page 11
اور نمکین ہو تو اس صورت میں تمام گرم دواؤں کے مزاج معلوم نہیں ہو سکتے.کیونکہ بعض گرم چیزیں تلخ و تیز نہیں
ہوتیں.مثلاً چڑیوں ، مرغ اور دوسرے حیوانات کے گوشت.اس نے ان لوگوں پر سخت تنقید کی ہے جنہوں نے تلخ
چیزوں کو صرف حار کہا ہے.افیون کی مثال دیتے ہوئے اس نے لکھا ہے کہ افیون کا ذائقہ بہت تلخ ہے لیکن متفقہ طور
پر وہ بار د اور مخدر ہے.کتاب الکلیات میں جالینوس اور ابن زہر کے حوالے ملتے ہیں لیکن پوری کتاب میں ابن سینا یا مشرق
سے کسی طبیب کا حوالہ نہیں پیش کیا گیا ہے.کٹر محب وطن اندلسی تھا.افلاطون نے یونان کو سائنس اور عقلی علوم
کا سب سے بڑا گہوارہ قرار دیا تھا.نے اندلس کو علم کا عظیم ترین مرکز کہا.جالینوس نے سب سے اچھی آب د
ہوا کا ملک یونان کو بتایا تھا.نے آب و ہوا کی عمدگی کے لحاظ سے قرطبہ کی افضلیت ظاہر کی.اسے ابن سینا
کی بالادستی تسلیم نہیں تھی.اس نے محض ابن سینا کی القانون کے جواب میں خود کتاب الکلیات تصنیف کی اور اپنے ہم
عصر اور دوست ابن زہر سے جس کی علمیت سے دوستاثر تھا، معالجات پر لکھنے کی فرمائش کی.چنانچہ اس نے کتاب
التیسیر جیسی کتاب تصنیف کی.ابن زہر نے انتیسیر کے مقدمے میں اعتراف کیا ہے کہ اس نے اپنے دوست کی
فرمائش پر یہ کتاب لکھی ہے.کتاب الکلیات کے آخر میں خود نے کتاب استیسیر کی تعریف اور اس کے
مطالعہ کی سفارش کی ہے.مقصد صرف یہ تھا کہ یہ دونوں کتا میں مل کر القانون کا مقابلہ کر سکیں اور اس کے مطالعہ کی
احتیاج باقی نہ رہے.کثیر التصانیف مصنف ہے.اس کے تحریر کردہ صفحات کی تعداد میں ہزار سے
کم نہیں ہے.طب میں مقالہ فی المزاج ، مقالہ فی نوابت اٹھی ، مقالہ فی حمیات العفن ، مقالہ فی الترياق ، شرح کتاب الاستقسات
لجالینوس ،
شرح کتاب
المزاج الجالينوس بالخيص كتاب القوى الطبيعيه بتلخيص كتاب العلل والاعراض الجالينوس التلخيص
کتاب العرف الجالینوس
، تلخیص کتاب المیات لجالینوس ،تلخیص اول کتاب الادوو یه المفرده لجالینوس، تلخیص کتاب
حیلة البره الجالینوس (نصف آخر ) شرح ارجوز و ابن سینا اور کتاب الکلیات وغیرہ ہیں.اس کی کتاب الادویہ کے
مخطوطہ کو مجھے ترکی کے سفر میں کتب خانہ احمد ثالث استنبول میں دیکھنے کا موقع ملا تھا.ہندوستان میں صرف آخری دو کتابیں طبع ہوئی ہیں.شرح ارجوزہ لکھنو سے 1241ھ / 1845ء
میں چھپی ہے اور کتاب الکلیات کی عربی اشاعت (1984ء) اور اردو ترجمہ (1987 ء ) مرکزی کونسل برائے تحقیق
طب یونانی، نئی دہلی کے لائق افتخار علمی کاموں میں ہے.موخر الذکر دو کتابوں کے علاوہ کی کتاب مابعد
المطبعيات ( تلخیص مقالات ارسطو) کی ایک قدیم اشاعت جو تبت صبح مصطفی قبانی دمشقی مطبع ادبیہ مصر سے طبع ہوئی
ہے، ابن سینا اکاڈمی علی گڑھ میں محفوظ ہے.فلسفہ میں اس کی تین کتابوں فصل المقال ، منابج الادلہ اور تہافتہ انتہافتہ کو خاص اہمیت حاصل ہے.پہلی
(iv)
Page 12
کتاب میں اس نے فلسفہ و شریعت کے باہمی تعلق پر روشنی ڈالی ہے.اور بعض جگہ تطبیق کا انداز اختیار کیا ہے.دوسری میں
اسلامی عقائد کو عقلی دلائل کی رو سے صحیح ثابت کرنے کی کوشش کی ہے.تیسری غزالی کی تہافتہ انتہافتہ کی تردید میں ہے.کے فلسفہ کی یورپ میں خوب اشاعت ہوئی.اس کی کتابوں کے عبرانی ، لاطینی اور دوسری
مغربی زبانوں میں تو جسے کئے گئے.ان کی شرحیں اور خلاصے لکھے گئے.اور انہیں بہت توجہ اور شوق سے پڑھا گیا.محمد ذکر با درک مسلمانوں کی علمی تاریخ کے شناور اور بڑے کثیر المطالعہ محقق ہیں.مسلمانوں کے سائنسی
کارناموں پر انہوں نے جو تحقیقی کام کیا ہے اور حصول مواد کے لئے جو جدو جہد اور کوشش صرف کی ہے، اس سے متعلقہ
مضمون سے ان کے غیر معمولی شغف کا اظہار ہوتا ہے.ان کے مطالعہ کی بہت خاص بات یہ ہے کہ انھوں نے ان
اہم ماخذ تک رسائی حاصل کی ہے جو عام طور پر مشرقی محقیقین کی پہنچ سے باہر ہیں.چونکہ وہ ایک عرصہ سے کناؤ میں
مقیم ہیں اس لئے بڑی آسانی سے انہیں مغربی ملکوں کے کتب خانوں میں تلاش مواد کا موقع ملا.اور انھوں نے وہاں
مسلم سائنس دانوں کے جو مخطوطات یا قدیم مطبوعات مختلف زبانوں میں محفوظ ہیں ان کے بارے میں براہ راست
واقفیت ہم پہنچانے کی کوشش کی.ان کی کتاب " مسلمانوں کے سائنسی کارنامے " جو مرکز فروغ سائنس، علی گڑھ مسلم
یونیورسٹی سے گذشتہ سال 2005 ء میں شائع ہوئی ، ان کی تاریخی معلومات ، وسعت مطالعہ اور ماخذ کی تلاش میں ان
کی قابل تحسین کا دشوں کا آئینہ ہے.مجھے خوشی ہے کہ مرکز فروغ سائنس کی فرمائش پر انہوں نے کو اپنی تحقیق
کا موضوع بنایا.کی شخصیت اور اس کی علمی و سائنسی خدمات پر ان کی یہ تصنیف رینان کے بعد دوسری اہم
کتاب کا درجہ رکھتی ہے.امید ہے اس کے ذریعہ کے ساتھ مسلمانوں کے سائنسی کارناموں کے مطالعہ سے
دلچسپی بڑھے گی اور عظمت رفتہ کی بحالی اور علمی وراثت کی حفاظت کا جذبہ فروغ پائے گا.مرکز فروغ سائنس کے
سابق ڈائرکٹر پروفیسر سید محمد ابوالباشم رضوی اور موجودہ ڈائرکٹر ڈاکٹر شاہد فاروق شکریہ کے مستحق ہیں، جن کے زیر
اہتمام یہ کتاب شائع ہو رہی ہے.ابن سینا اکاڈمی
علی گڑھ
:
سید ظل الرحمن
اکتوبر ۲۰۰۶
Page 13
چندا ہم تاریخیں
یوسف ابن تاشفین مراقش شہر کا مؤسس اور المرابطون سلطنت کا بانی
علی ابن یوسف کا دور حکومت جس نے اسپین اور مراقش کے درمیان سیاسی اتحاد پیدا کیا کی قرطبہ میں پیدائش.پورا نام ابو ولید محمد بن احمد بن محمد بن رشد الحقيد
مراقش کا زوال، الموحد دور سلطنت کا آغاز
وکالت کے پیشہ سے وابستگی اور مقدمات کی دارالقضاء میں سماعت بائیس سال کے تھے جب موحدین نے قرطبہ پر قبضہ حاصل کیا
27 سال کی عمر میں کی مراتش میں آمد علم بعیت پر تحقیقی کام
ارسطو کی بارہ کتابوں
کی تلخیص لکھی جیسے مختصر فی المنطق مختصر الشعر
جبل الطارق شہر کی بنیاد رکھی گئی.مراقش میں کلیات فی الطب کا پہلا مہ: وہ تیار کیا
خلیفہ عبد المومن کے دور خلافت کا خاتمہ
کلیات فی الطب کا پہلا مسودہ
خلیفہ ابو یعقوب یوسف کا دور خلافت
كتاب بداية المجتھد کی تصنیف اس کی تیاری میں میں سال صرف ہوئے تھے.این رشد کا اشبیلیہ کے منصب قضاء پر تقرر
قرطبہ کا قاضی اور کچھ عرصہ بعد قاضی القضاة (1180ء) مقرر کیا گیا.ارسطو کی
ما بعد الطبعیات کی شرح لکھی
مراقش روانگی.ابن طفیل کے بعد ابو یعقوب یوسف کے دربار میں شاہی طبیب مقرر کیا
گیا مگر کچھ عرصہ بعد قرطبہ کے قاضی القضاۃ ( چیف جسٹس) کے عہدہ پر تقرری کی وجہ
سے واپسی
خلیفہ ابو یوسف یعقوب المنصور کا دور خلافت - تہافتہ انتہافتہ تصنیف کی (1184).(vi)
1062-1106
1106-1142
1126
1147
1144-1153
1148
1153-1154
1157
1159
1130-1163
1162
1163-1184
1167
1169-1170
1172-1182
1182
1184-1199
Page 14
افلاطون کی کتاب المجمہوریہ کی شرح مکمل کی
کلیات فی الطب کی تکمیل.کا دور ذلت ورسوائی ، لوسینا کے شہر میں جلا وطنی کے ایام ، فلسفہ کی کتابیں
نذر آتش
خليفه المنصور نے مراقش جا کر کو بحال کیا اور اپنے پاس بلایا.اسی سال دسمبر
میں کی مرافقش میں وفات اور تدفین.کی قرطبہ میں تدفین، جنازہ میں محی الدین ابن العربی کی شرکت
(vii)
1191
1194
1195-1197
1198
1199
Page 15
+1126
1127ء
+1130
+1140
₤1143
+1145
+1150
1158
+1167
+1168 کے زمانے کے عالمی واقعات
ایڈے لارڈ آف ہاتھ (برطانیہ) نے الخوارزمی کی زج کا ترجمہ کیا ، اس کے بعد اس
نے کتاب الجبر والمقابلہ کا عربی سے لاطینی میں ترجمہ کیا.اسٹیفن آف انیاک Antioch نے علی بن عباس مجوسی کی کتاب الملکی کالاطینی میں
ترجمہ کیا
الخوارزمی کی زج کی مسلمہ الحجر یعطی (اندلس) کی شرح کا ایڈے لارڈ آف ہاتھ نے
ترجمہ کیا
سلی کے شہنشاہ راجر دوم نے حکم دیا کہ طلب کی پریکٹس صرف وہ لوگ کریں گے جنہوں
نے حکومت سے لائسنس حاصل کیا ہوگا.اسلامی ممالک میں ایسے لائسنس تین سو سال
قبل جاری ہو چکے تھے.رابرٹ آف چیسٹر نے قرآن مجید کالاطینی میں پہلا ترجمہ کیا.(اگر چہ ترجمہ میں فاش غلطیاں
تھیں)
رابرٹ آف چیسٹر نے الخوارزمی کی الجبر اپر کتاب کا ترجمہ کیا.اصفہان کی جامع مسجد کا
سنگ بنیاد رکھا گیا.اندلس کے ہیئت وال جابر بن افلح کی اشبیلیہ میں وفات.اس نے کتاب الہیئتہ میں
بطلیموس کی تھیوری آف پلے نفس پر کڑی تنقید کی.اس نے ایک ہئیت کا آلہ ایجاد کیا جس
کا نام Turquet ہے.اٹلی میں یونیورسٹی آف بولونیا کا سنگ بنیاد رکھا گیا.اس کا نصاب اسلامی جامعات کے
طرز پر تھا.برطانیہ میں آکسفورڈ یونیورسٹی کا آغاز.ڈے نیل مورلی اور یہودی محققین نے یونیورسٹی کے لئے اسلامی علوم کی تعلیم لازمی قرار دی.(viii)
Page 16
جیرارڈ آف کریمونا نے عربی کتابوں کے تراجم لاطینی میں شروع کئے.ان کتابوں کے
مصنفین الکندی ، ثابت ابن قرة، الحق ابن حنین محمد بن زکریا رازی ، الفارابی، بوعلی سینا
وغیرہ تھے.سلطان صلاح الدین ایوبی نے دمشق فتح کیا
اشبیلیہ کی جامع مسجد کا سنگ بنیاد رکھا گیا، مسجد کے مینار لا جیرالڈا (La Giratda
کی تعمیر شروع ہوئی ( تحمیل 1184)
انگلش محقق مائیکل سکاٹ کی ولادت ، آکسفورڈ اور پیرس میں تعلیم مکمل کی ، عربی زبان
سیکھی اور سسلی میں قیام کے دوران کئی مصنفین (ارسطو، ، البطر وجی) کی
کتابوں کے تراجم کئے.ڈے نیل مورلی ( برطانوی محقق) نے جو اسلامی علوم و فنون سے بہت متاثر تھا، آکسفورڈ ،
پیرس، اور ٹولیڈ و (طلیطلہ) میں تعلیم حاصل کی عربی کتابوں کے تراجم کئے.آکسفورڈ یو نیورٹی کی بنیاد رکھی گئی.ہندوستانی ریاضی دان بھاسکر اچاریہ کی اجین میں وفات
جیرارڈ آف کریمونا کی طلیطلہ میں وفات ، اس نے قریب ستر یونانی اور عربی کتابوں کا
لاطینی میں ترجمہ کیا تھا.سلطان صلاح الدین نے یروشلم فتح کیا.ایرانی شاعر نظامی نے لیلی و مجنوں رزمیہ نظم مکمل کی.فرانس کے شہر ہیرالٹ (Herauit) میں کاغذ کی فیکٹری کا آغاز.اچین سے باہر
یورپ میں یہ پہلی مل تھی.تیسری صلیبی جنگ کا آغاز.سلطان صلاح الدین کی وفات
ابویوسف یعقوب نے الفانسو ہشتم کو طلیطلہ میں شکست فاش دی اور منصور کا خطاب پایا.کی مراتش شہر میں وفات
(ix)
1170
1173
+1172
1175
+1180
,1185
+1187
1188ء
+1189
r
+1193
+1195
,1198
'
Page 17
کے حکیمانہ اقوال
زندگی میں صرف دو دن مطالعہ نہیں کر سکا، ایک جس روز میری شادی ہوئی اور دوسرے جس روز
میرے باپ نے وفات پائی.اگر میں دوستوں کو کچھ عطا کروں تو یہ ایک سپند اور خوشگوار فریضہ ہوگا.احسان تو یہ ہے کہ دشمنوں کے
ساتھ اچھا سلوک کیا جائے جس کو طبیعت مشکل سے گوارا کرتی ہے.علم تشریح ( اناٹومی ) کی واقفیت سے اللہ تعالی پر انسان کا ایمان اور قومی ہو جاتا ہے.دوست کی طرف سے جو تکلیف پہنچتی ہے وہ دشمن کی دی ہوئی تکلیف سے زیادہ تخت ہوتی ہے
فلسفہ شریعت کی سہیلی اور اس کی رضاعی بہن ہے.(ان الحكمة هي صاحبة الشريعة
والأخت الرضيعة.Philosophy is the friend & foster sister of religion
ہر پیغمبر فلسفی ہوتا ہے لیکن ضروری نہیں کہ ہر فلسفی پیغمبر بھی ہو
Every prophet is a sage but not every sage is prophet.راستی سچائی کی مخالفت نہیں کرتی بلکہ اس کی ہم تو ہوتی ہے اور اس کے حق میں گواہی دیتی ہے.علم مفعول بہ اور عقل میں تطبیق کا نام ہے
Knowledge is the conformity of the object and intellect.حقیقی مسرت کا حصول ذہنی اور نفسیاتی صحت سے ہی ممکن ہے.نفسیاتی صحت اس وقت تک حاصل
نہیں ہوسکتی جب تک لوگ ایسی راہوں
پر عمل پیرا نہ ہوں جو آخرت میں خوشی کی طرف لے جاتی ہیں.اور جب تک خدا اور اس کی وحدانیت پر ایمان پختہ نہ ہو.خدا اس کائنات کا نظم ونسق توانائی اور نفس ہے God is the order, force and mind
(x)
of the universe
Page 18
ترتیب کے حالات زندگی
باب اول
باب دوم بحیثیت مصنف اور فقیہ
باب سوم بحیثیت طبیب
باب چہارم بحیثیت سائنس داں بحیثیت فلسفی و شارح ارسطو
باب پنجم کے نظریات یورپ میں
باب ششم
باب
ہفتم
: عصر حاضر میں
ماخذ و مصادر
61
91
1
35
-362a
72
120
129
136
Page 19
باب اول کے حالات زندگی
محمد اسلامی اندلس کا سب سے عظیم فقیہ فلسفی ، طبیب، ماہر فلکیات، قانون داں، قاضی ، مصنف اور
ارسطو کی کتابوں کا شارح تھا.لاطینی میں اسے ایوروز ( Averoes ) اور اچینی میں ایون روز (Aven Ruiz)
کہا جاتا ہے.اسلامی دنیا میں اس کی شہرت بطور فقیہ اور یورپ میں بطور فلسفی ہے.بارہویں صدی سے سولہویں صدی
تک یورپ میں اس کا طوطی بولتا رہا.اس کے سیاسی ، سماجی ، علمی، فلسفیانہ نظریات سے اہل یہود اور اہل نصاری نے
بہت استفادہ کیا جس سے یورپ کی نشاۃ ثانیہ ممکن ہوئی.یورپ کی علمی اور مادی ترقی در اصل اس کی ارسطو کی شرح
کردہ کتابوں کی رہین منت ہے.اس کا اصل نام محمد اتنا مشہور نہیں جتنی کہ اس کی کنیت معروف ہے.اس کی وجہ یہ ہے کہ منصور ابن ابی
عامر کے عہد حکومت کے بعد اندلس میں یہ دستور رواج پذیر ہوگیا تھا کہ خاندان میں جس شخص کی پہلے شہرت ہوتی اسی
کی جانب اس خاندان کے تمام افراد کے ناموں کا انتساب کیا جاتا.اس بناء پر کا انتساب اپنے دادا محمد ابن
رشد قرطبی کی جانب کیا جاتا ہے جس کی کنیت ابو دلید اور لقب حفید تھا.اسلامی اسپین کے دارالخلافہ قرطبہ میں 1126ء میں شمع افروز بزم جہاں ہوا اور اپنے وجود باجود سے
عالم کو روشن کیا.دنیا کو اپنے علم سے سات دہائی تک روشن کرنے والا یہ چمکدار ستارہ 10 دسمبر 1198 کو مراقش
میں مطلع فانی سے اوجھل ہوا.اندلس میں اس کا خاندان پشت ہا پشت سے علوم وفنون کا مربی تھا.اس کے والد ماجد
احمد ایک ذی علم شخص تھے.نے ابتدائی تعلیم گھر میں حاصل کی اور اپنے والد ماجد سے قرآن مجید اور موطا امام
مالک کو حفظ کیا.اس کے بعد عربی ادب میں کمال حاصل کیا.ممتاز عربی شعراء منبتی اور حبیب کے دیوان اس کی نوک
زبان تھے.علم فقہ اور علم حدیث کے خاندانی علم تھے.عبد الواحد المراقشی اور الذہبی نے کے
جو حالات زندگی قلم بند کئے ہیں ان میں اس کے نتھیال اور والدہ کا تذکرہ کہیں بھی نہیں ہوا ہے.والد احمد
Page 20
قائنی کے عہدے پر فائز رہے.کسی بھی مورخ نے کے خاندانی نسب کا ذکر نہیں کیا ہے.نامورا اندلسی مورخ المقری نے نفح
الطیب میں لکھا ہے کہ جو لوگ قبیلہ کنانہ کی طرف منسوب ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے.اور وہ زیادہ تر طلیطلہ
میں آباد ہیں اور قاضی ابو الولید انہی لوگوں کی طرف منسوب ہیں.اس سے پتہ چلتا ہے کہ عربی النسل تھے.مزید برآل ابن طفیل کی سفارش پر جب امیر السلمین عبدالمومن کے دربار میں حاضر ہوا تو ابن طفیل نے اس
کے تعارف میں اس کے خاندان اور آباء و اجداد کی تعریف کی تھی.کے فرانسیسی سوانح نگار ارنسٹ رینان
نے اس کے عربی النسل ہونے کی یہ دلیل پیش کی ہے کہ عبدہ قضاء جس پر اس کے باپ اور دادا مامور تھے ایسا اہم
عہدہ تھا جس پر صرف قدیم اسلامی خاندان کے لوگ ہی فائز ہوتے تھے.(1) کا خاندان کے داد امحمد بن رشد قرطبی ( کنیت ابو ولید ( خداد اد شہرت کے مالک اور مالکیہ مذہب کے امام تھے.ان کی پیدائش قرطبہ میں 1058ء میں ہوئی.وہ اندلس اور مغرب کے یگانہ روزگار فقیہ اور مفتی اعظم تھے.عوام
اور خواص مشکل مسائل کے حل کے لئے ان سے رجوع کرتے تھے.ان کی مذہبی اور اخلاقی حیثیت بھی بہت بلند
تھی.سفر و حضر میں ہمیشہ جمعہ کا روزہ پابندی سے رکھتے تھے.انہوں نے حافظ ابو جعفر بن رزق سے فقہ کی تعلیم مکمل
کی.ابو عبد الله بن فرج، ابو مروان بن سراج، ابوالعافیہ جو ہری سے حدیث سنی اور عذری نے ان کو حدیث کی سند عطا
کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد انہوں نے درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا.ان کے ایک نامور شاگرد کا نام قاضی
عیاض مالکی تھا.ابومردان عبد الملک بن مسرہ اور ابن بشکوال بھی ان کے شاگر درشید تھے.انہوں نے متعدد کتابیں زیب قرطاس کیس جیسے فقہ کی کتاب اليان والتفصيل لـمــا فــي
المستخرجة من التوجيه والتعلیل نہیں جلدوں میں ہے جس میں صحابہ تابعین اور تبع تابعین کے فقہی
اختلافات بیان کئے ہیں اور ان کا محاکمہ کیا ہے.اجتہاد کی شان یہ ہے کہ آیات، احکام، اور احادیث کی اصولی
واقفیت کے ساتھ صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کے اقوال پر مکمل عبور حاصل ہو، اس نسبت سے محمد بن رشد مجتہدین کی
صف میں شمار ہوتے تھے.نے اپنی کتاب بدایۃ المجتہد میں دادا کے اجتہار کی ایک عمدہ مثال پیش کرتے
ہوئے لکھا ہے: قرطبہ میں ایک حادثہ میں مقتول کے بعض ورثاء بالغ اور شرعا دعوئی قصاص کی اہمیت رکھتے تھے اور
بعض نا بالغ اور غیر مختار تھے.یہ مسئلہ جب عدالت میں پیش ہوا تو تمام نانا نے فتوی دیا کہ چونکہ بعض اولیاء دم بالغ
ہیں اور ان کو اخذ ریت کا قاتل کی رضامندی کے بغیر اختیار نہیں اس لئے قصاص میں تا خیر نہیں کرنی چاہئے.لیکن
2
Page 21
محمد بن رشد تنہا اس متفقہ فیصلے کے خلاف تھے.ان کی رائے تھی کہ اس معاملے میں انتظار کرنا چاہنے یہاں تک کہ
نابالغ اولیائے دم قصاص لینے کے قابل ہو جائیں ممکن ہے ان کی خواہش قصاص لینے کی نہ ہو.یہ رائے سراسر شخصی
اجتہاد پر منی تھی اور مصلحت اور شریعت دونوں کے لحاظ سے قابل قبول تھی.تا ہم علما ناراض ہو گئے.اس کے بعد محمد بن
رشد نے ایک خاص رسالہ
لکھ کر اپنی رائے ثابت کی.ان کی ایک اور مایہ ناز تصنیف کا نام کتاب المقدمات لا وائل كتب المدونة ہے.اس وقت یہ
دونوں کتابیں عنقا ہیں.البتہ بارہویں صدی میں قرطبہ کی جامع مسجد کے امام ابن القران نے ان کے فتاوی کا مجموعہ
مرتب کیا تھا جو پیرس کی امپیرئیل لائبریری میں موجود ہے.بیان کیا جاتا ہے کہ محمد بن رشد روایت پرست نہ تھے
بلکہ روایت ( تقلید ) سے زیادہ ان میں درایت (عقلیت) پائی جاتی تھی.درایت کا یہی ورثہ نے اپنے دادا
سے پایا تھا.محمد کو شاہی دربار میں تقرب حاصل
تھا اور وہ امیر السلمین کو سیاسی و انتظامی معاملات میں اہم
مشوروں سے نوازتے تھے.چنانچہ ایک دفعہ خانہ جنگی کے دوران سرکش باغیوں نے ان کو خلیفہ کے پاس مراتش میں
پیام مصالحت دے کر بھیجا اور وہ اپنے سفارتی مشن میں کامیاب ہو کر واپس لوٹے.سیاسی زندگی میں ان کی اصابت
رائے کا ایک اور واقعہ یہ ہے کہ کیسٹیل (Castile) کا عیسائی بادشاہ اسلامی علاقوں پر حملے کرتارہتا تھا.ان علاقوں
میں آباد عیسائی چونکہ اس کی مدد کرتے تھے اس لئے وہ ان حملوں میں کامیاب رہتا تھا.محمد بن رشد نے پیش آمد ملکی
حالات کا جائزہ لے کر 31 مارچ 1126ء کو مراکش کا سفر کیا اور خلیفہ کو مشورہ دیا کہ اسلامی علاقوں میں آباد عیسائیوں کو
اندلس سے منتقل کر کے شمالی افریقہ میں آباد کیا جائے.خلیفہ کو یہ سیاسی مشورہ بہت پسند آیا اور ہزاروں عیسائی
طرابلس، المغرب اور بربری علاقوں میں آباد کر دئے گئے جس کے نتیجے میں اندلس میں سیاسی استحکام پیدا ہو گیا.ان کے سیاسی اثر و رسوخ کا ایک اور واقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب اندلس کے نامور فلسفی ابن باجہ (لاطینی نام
Avenpace ) پر الموحد حکمران خلیفہ ابراہیم ابن یوسف کے دور میں بدعت اور کفر کا التزام عائد ہوا اور اسے پابند
سلاسل کیا گیا تو محمد بن رشد کی سفارش سے ہی اسے قید سے رہائی ملی تھی.محمد بن رشد قرطبہ کی جامع مسجد کے امام اور بہت کم خن، با حیا اور پاکباز تھے.1121ء میں قرطبہ کے قاضی
مقرر ہوئے مگر شہر میں ایک شورش برپا ہونے پر 1125ء میں اس عہدے سے خود ہی سبکدوش ہو گئے.انہوں نے
1126ء میں داعی اجل کو لبیک کہا اور مقبرہ عباس میں آسودہ خاک ہوئے.ان کے بیٹے ابوالقاسم (احمد ابن
رشد ) نے نماز جنازہ پڑھائی اور سیکڑوں افراد نماز جنازہ میں شریک ہوئے.ان کے عظیم المرتبت ہونے کی پیدائش
ان کی وفات سے ایک ماہ پیشتر ہوئی تھی.3
Page 22
محمد بن رشد کو شاہی دربار میں خاص رتبہ حاصل تھا.الدیباج الذہب میں لکھا ہے: مقدماً عند امیر
من
المسلمين - عظيم المنزلة معتمداً في العظائم ايام حياته واليه كانت الرحلة للتفقه
اقطار الاندلس مدة حياته.".و بادشاہ کے نزدیک نہایت معزز تھے اور امور سلطنت میں ساری زندگی ان
پر اعتماد کیا جاتا تھا.لوگ فقہ کا علم حاصل کرنے کے لئے اندلس کے اطراف و جوانب سے عمر بھر ان کی رحلت تک ان
کے پاس آتے تھے."
دادا اور پوتے میں پانچ باتیں مشترک تھیں : دونوں کا نام مجھ تھا.جس سال دادا اللہ کو پیارے ہوئے اس سال
پوتے کی پیدائش ہوئی.دونوں قاضی القضاۃ کے عہدے پر متمکن رہے.دادا نے بھی کتب تصنیف کیں اور پوتے
نے بھی.دادا کے بیٹے کا نام احمد تھا اور پوتے کے فرزند کا نام بھی احمد تھا.کی تعلیم اور اساتذہ
اندلس میں اس دور میں بچوں
کی ابتدائی تعلیم کا طریقہ کار یہ تھا کہ بچے کو پہلے قرآن مجید حفظ کراتے تھے.اس
کے بعد اس کو صرف و نحو اور ادب
و انشاء کی تعلیم دی جاتی تھی.چونکہ اندلس میں مالکی مذہب رائج تھا اس لئے بچوں
کو موطا امام مالک بھی حفظ کرائی جاتی تھی.جب طالب علم فنون ادب کی تعلیم مکمل کر لیتا تو اس کے بعد جس فن میں
اس کا فطری میلان ہوتا وہ اسے حاصل کرتا تھا.کی ابتدائی تعلیم ملک میں رواج شدہ نصاب تعلیم کے مطابق شروع کی گئی.انہوں نے اپنے والد ماجد
ابوالقاسم سے قرآن مجید اور حدیث کی کتاب موطا کو حفظ کرنا شروع کیا.اس سے فراغت پانے کے بعد انہوں نے
عربی زبان اور علوم ادبیہ کی طرف توجہ کی اور اس میں اتنا کمال حاصل کیا کہ بچپن میں ہی شعر گوئی کرنے لگے.تاہم
بچپن کے زمانے میں لکھے گئے ان اشعار کو جو اخلاقی غزلیات پر مشتمل تھے بعد میں نذرآتش کر دیا.مؤرخ ابن الا بار
نے لکھا ہے کہ ان
کو تنبی اور حبیب کے اشعار نوک زبان تھے اور اکثر محفلوں میں دو ان اشعار کو برجستہ موقعہ محل کے
مطابق پڑھ کر داد تحسین حاصل کرتے تھے.ان
کو دور جاہلیت کے شعراء کے کلام پر بھی عبور حاصل تھا چنانچہ ان کی
تصنیف کتاب الشعر میں امراؤ القیس ، اشی، ابو تمام متنتی اور اصفہانی ( الاغانی) کے اشعار بکثرت پائے جاتے
ہیں.ابتدائی تعلیم سے فراغت کے بعد انہوں نے اعلی تعلیم حاصل کرنا شروع کی.اس زمانے کے اطباء اور فلاسفہ
کی سوانح کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ طب وفلسفہ میں مہارت رکھنے کے علاوہ محدث اور فقیہ بھی ہوتے تھے.چنانچہ کے دوست اور قرون وسطی کے عظیم طبیب ابو مروان ابن زہر کو حدیث وفقہ پر عبور حاصل تھا.اس
4
Page 23
وقت فقہ اور حدیث بنیادی تعلیم کا لازمی حصہ خیال کئے جاتے تھے.چنانچہ فقہ اور حدیث کی تعلیم انہوں نے اپنے
وقت کے نامور محدثین حافظ ابن بشکوال ، ابومروان عبد الملک ، ابوبکر بن سمحون ، ابو جعفر بن عبد العزیز ، ابو عبد الله
الماذری اور حافظ ابومحمد بن رزق سے حاصل کی.ابن الآبار کا کہنا ہے کہ کو درایہ ( سائنس آف لا) میں زیادہ
دلچسپی تھی بجائے روایہ کے (سائنس آف ٹریڈیشن ).ابو عبد الله ماذری (1139ء ) طب و حساب میں مہارت رکھتے تھے.فقہ حدیث اور تحقیق فقہ میں ان کو مجتہد کا
رتبہ حاصل تھا.انہوں نے شرح صحیح مسلم لکھی جس پر بعد میں آنے والے محدثین جیسے ابن حجر نے اپنی تحقیقات کا سنگ
بنیا درکھا.ابو مروان عبد الملک بن مسرہ (1155ء) حدیث وفقہ کے علاوہ فن رجال میں ماہر تسلیم کئے جاتے تھے.حافظ ابوالقاسم ابن بشکوال (1182-1101ء) قرطبہ کے رہنے والے مگر اشبیلیہ میں قاضی کے عہدے پر
مامور تھے.دو اندلس کے ممتاز محدث ، ناقد حدیث، اور مورخ تھے.انہوں نے پچاس کتا ہیں ورثہ میں چھوڑیں
جیسے رواء الموطلا موطا امام مالک کے قاری اور کتاب الصیله فی اخبار آئمة الاندلس جس میں
1139 ء تک کے اندلس کے 1541 عالموں، ادیبوں اور دانشوروں کا ذکر کیا گیا ہے.کتاب مصنف کی گل افشانی
گفتار کا شاہکار ہے.اس کے تعارف میں اس نے لکھا کہ یہ کتاب اس نے اپنے مداحوں کی فرمائش پر ابن الفرضی کی
کتاب تاریخ علماء اندلس کے عملہ کے طور پر لکھی تھی اسی لئے اس کتاب کا انداز ( رسم وطریقہ ) الفرضی کی تاریخ علما
اندلس جیسا ہے.دونوں کتابوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا رہا.متعدد عالموں نے ذیل کتاب الصیلہ کے طور پر
کتابیں رقم کیں.اشبیلیہ میں وہ اور ابو بکر ابن العربی کا تنقیح ساز تھا.اندلس کی ثقافتی تاریخ پر اسے سند مانا
جاتا تھا جس کے پیش نظر اس کو ملک کے علمی حلقوں میں بڑی وقعت حاصل تھی.(2).کتاب الصیلہ میڈرڈ سے دو
جلدوں میں 1883ء میں شائع ہوئی تھی.نے اس کے علاوہ اصول اور علم کلام کی تعلیم بھی حاصل کی لیکن ان علوم میں ان کے اساتذہ کے اسماء
نا معلوم ہیں.طب اور یونانی علوم ( منطق، فلسفہ) کی تعلیم کے لئے انہوں نے ابو مردان بن جریول اور ابو جعفر ابن
ہارون التر جالی (Trujillo) سے اکتساب کیا.التر جالی کا تعلق اشبیلیہ کے معزز خاندان سے تھا اور شہر کے سر کردہ
افراد میں اس کا شمار ہوتا تھا.بطور فلسفی وہ حکمت کے علوم ( فلسفہ، منطق) میں کمال رکھتا تھا اور حکماے متقدمین
( ارسطو، افلاطون ) کی کتابوں کا ماہر تھا.بطور طبیب اس کو معالجہ میں کمال حاصل تھا.آنکھوں کے علاج ( صنعت
الكحل ) میں خصوصی مہارت تھی.کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک بچے کی آنکھ کے ڈھیلے میں لکڑی کا چھوٹا ٹکڑا گھس گیا
التر جالی نے اللہ کی نصرت سے اس کا ایسا شافی علاج کیا کہ بینائی بحال ہوگئی.الموحد خلیفہ ابو یعقوب یوسف کے
دربار میں اسے خاص مقام حاصل تھا.فقہ کے معاملات میں وہ ابو بکر ابن عربی کا شاگر د تھا.(3)
5
Page 24
نے خاندانی علوم (فقہ وحدیث ) کی تحصیل کے بعد طب فلکیات، ریاضی، موسیقی علم الحیوانات اور
فلسفہ کی اعلیٰ تعلیم کی طرف توجہ کی اور فطری استعداد کے سبب بغیر کسی مزید کوشش کے طب اور فلسفے میں مہارت تامہ
حاصل کی.اس وقت اسلامی اسپین میں فلسفہ و منطق کی تعلیم کا رواج ہو چکا تھا اور علما وعوام کی مخالفت کے باوجود
طالب علم یہ علوم بڑے شوق سے حاصل کرتے تھے.بعض مؤرخین کا خیال ہے کہ فلسفہ ( علوم الحکمیہ ) کی تعلیم ابن
رشد نے اندلس کے سب سے عظیم فلسفی ابو بکر ابن باجہ (1138-1100 ء ) سے حاصل کی تھی.علامہ ابن ابی اصیبعہ
نے طبقات الاطباء میں لکھا ہے کہ نے ابن باجہ کی شاگردی کی تھی.مگر یورپ کے مورخین اس بات
کو تسلیم
نہیں کرتے کیونکہ کی پیدائش 1126ء میں ہوئی جبکہ ابن باجہ کی وفات 1138 ء میں ہوئی.اس امر کے
پیش نظر کی عمر ابن باجہ کی رحلت کے وقت بارہ برس تھی جو کہ فلسفہ جیسے دقیق علم کے حصول کے لئے موزوں عمر
نہیں ہے.محمد لطفی جمعہ تاریخ فلاسفة الاسلام میں لکھتے ہیں : یہ یقینی ہے کہ ابن باجہ کے گھر آیا جایا کر
تا تھا ، اس لئے اگر اس نے بچے سے گفتگو کر لی ہو یا اس سے کوئی سبق یا قصیدہ سن لیا ہو تو یہ کوئی دور کی بات نہیں ہے.یہ واقعہ یا اس قسم کے جو واقعات بار بار پیش آئے وہ شاگردی کی طرف منسوب ہو جانے کا سبب ہو گئے " (4)
اس زمانے میں مسلمان علوم کو دو حصوں میں تقسیم کرتے تھے: علوم نقلیہ (اسلامیات تفسیر، حدیث ) اور علوم
عقلیہ ( یونانی علوم، فلسفه دریاضی وغیرہ).جو شخص علوم نقلیہ کا ماہر ہوتا تھا وہ عالم کہلاتا تھا اور علوم عقلیہ کے ماہر کو حکیم
کہتے تھے.اس لئے حکمۃ سے مراد فلسفہ ہے یا پھر یونانی علوم کا علم.متقدمین حکماے اسلام فلسفے کو حکمت اور
حکمت کو خیر کثیر گردانتے تھے جیسا کہ قرآن حکیم میں ارشاد ہوا ہے " و من بوتى الحكمة فقد اوتي خيرا
كثيراً ".اس لئے جو قوم حکمت کی قدر نہیں کرتی وہ کفران نعمت کا ارتکاب کرتی ہے جس کا نتیجہ نا کامی ہوتا ہے.حکمت اپنی حقیقت میں نور معرفت ہے جو انسان کی شخصیت میں حسن و کمال پیدا کرتی ہے.قرآن کا ایک نام حکیم اسی
لئے ہے کیونکہ یہ علم و حکمت کے انمول خزانوں سے معمور ہے.یہاں یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ اسلام سے قبل دینی
علما کا یہ عقیدہ تھا کہ دین کے معاملے میں عقل سے کام لینا گمراہی کی طرف لے جاتا ہے.روایت جو کہے دی بچ
ہے چاہے عقل و حکمت کی رو سے وہ گمراہ کن ہی کیوں نہ ہو.اس طرح جب عقل کی اہمیت کا احساس جا تا رہا تو علوم
زوال پذیر ہو گئے.یہ قرآن حکیم ہی تھا جس نے علم و حکمت کی روشنی میں دین ودنیا کے ہر شعبے میں عقل و حکمت سے
کام لینے کی تلقین کی.دینی علوم کے علاوہ نے ریاضی، علم فلکیات ، منطق ، طبیعیات، طب کی تعلیم بھی قرطبہ کے مقبول
اساتذہ سے حاصل
کی مگر ان کے اسماء گرامی معلوم نہیں.عجیب بات ہے کہ نے اپنے اساتذہ میں سے کسی
ایک کا بھی ذکر اپنی کتابوں میں نہیں کیا.قرطبہ اس وقت علوم حکمیہ (عقلیہ ) کا مرکز تھا جبکہ اشبیلیہ ادبیات کے لئے
6
Page 25
مشہور تھا.اور ابن زہر کے درمیان اکثر علمی موضوعات پر مباحثہ (debate ) ہوا کرتا تھا.ایک دفعہ دونوں
میں اس موضوع پر مباحثہ ہوا کہ قرطبہ اور اشبیلیہ میں کون سا شہر اچھا ہے؟ دونوں نے دلائل پیش کئے ، نے
قرطبہ کے علمی، ادبی اور سائنسی ماحول کا ذکر کرتے ہوئے کہا : " جب کوئی عالم اشبیلیہ میں رحلت پاتا ہے تو اس کی
کتا ہیں قرطبہ بھیج ہی جاتی ہیں اور جب کوئی گویا ( معنی ) قرطبہ میں موت کی گود میں جاتا ہے تو اس کے آلات
موسیقی اشبیلیہ بھیج دئے جاتے ہیں".تلانده
اندلس میں اس زمانے میں بچوں
کو مسجد میں تعلیم دی جاتی تھی.شاگر وزمین پردائر ، بنا کر بیٹھتے اور استاد کسی اونچی
جگہ ( کرتی ) پر ایستادہ ہوتا تھا ، اس کو حلقہ کہا جاتا تھا.یورپ میں یونیورسٹیوں میں چیر ز (chairs) قائم کرنے کا رواج
اس کرین کی یادگار ہے.جب طالب علم تعلیم مکمل کر لیتا تو اسے اجازہ (licence) دیا جاتا، یورپ میں ڈگری اس کی نقل
ہے.گریجویٹ طالب علم پگڑی پہنتے تھے ، یورپ میں ہوڈ (hood) اسی کی یاد گار ہے.اعلیٰ تعلیم والے طلبہ (گر
یجوئیٹ ) استاد کے قریب اور مبتدی بپیچھے بیٹھتے تھے.کے دادا قرطبہ کی جامع مسجد میں درس دیا کرتے تھے.ممکن
ہے نے بھی قرطبہ کی کسی مسجد میں درس کے فرائض انجام دئے ہوں.اس زمانے میں درس کا طریق عموماً یہ ہوتا
تھا کہ استاد کسی خاص مسئلہ پر تقریر کرتا، شاگرد تقریر کے دوران سوالات کرتے اور جو کچھ استاد بتاتا اس کو زیب قرطاس
کرتے تھے.یہی لیکچر ( نوٹس ) بعد میں کتابی صورت میں شائع کئے جاتے تھے.کی کتابوں کے مطالعے سے
معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی زبانی لیکچر دیا تھا.چنانچ علم کلام کی دو کتا میں اس نے اس طرح قلم بند کیں.ارسطو (322-384
قبل مسیح) کی بعض شرحوں
کا انداز بیان بھی خطیبانہ ہے.ارسطو بھی نہیں ٹہل کر لیکچر دیا کرتا تھا.فقہ وحدیث میں کی مہارت کا یہ عالم تھا کہ پورے اندلس میں اس کا کوئی نظیر نہ تھا.متعدد تلامذہ نے
اس کے آگے زانوئے تلمذ تہ کیا ان میں ابو بکر بن جبور، ابومحمد بن حوط اللہ، سہیل بن مالک ، ابو الربیع بن سالم
ابو القاسم بن طیلسان ابن بندرد کے نام تاریخ کی کتابوں میں مذکور ہیں.فلسفہ منطق ، طب اور علم کلام پر
بھی لیکچر دیتا تھا.طب وفلسفہ میں اس کے نامور تلاند : میں سے کتاب تاریخ فلاسفة الاسلام میں احمد بن جعفر
صادق اور ابو عید اللہ الند ردمی کے نام دئے گئے ہیں.معاصرین
این رشد کا خاندان قرطبہ کے نامور اشراف اور باعزت خاندانوں میں شمار کیا جاتا تھا.صغرستی ہی سے اس کا
7
Page 26
اٹھنا بیٹھنا اچھی اور اعلیٰ سوسائٹی میں تھا.شہر کے لوگ اس خاندان کے تمام افراد کو سر آنکھوں پر بٹھاتے تھے.یادر ہے
کہ اندلس میں امیر اسلمین کے عہدے کے بعد قاضی القضاۃ کا عہد: سب سے اعلیٰ شمار کیا جا تا تھا.گو یا امیر یا خلیفہ
کی غیر موجودگی میں وہ اس کا نائب اور حکمران ہوتا تھا.کے دادا کا نام نہ صرف ان کی تصنیفات بلکہ ان کے
عہدہ جلیلہ کی وجہ سے پورے اندلس میں مشہور تھا.ابن زہر، ابن طفیل اور میں دانت کائی درسی تھی.ابن طفیل اور ابن زہر کا خاندان جاہ وحشمت اور علم وفضل
کی دولت سے مالا مال تھا.خاندان بنی زہر میں عبد الملک ( ابو مروان ) ابن زہر اور ابو بکر ابن زہر ممتاز حیثیت کے مالک
تھے.اس خاندان کا جد امجد ابو الاعلیٰ ابن زہر ( 1130ء) اشبیلیہ کا رہنے والا نہایت معزز محدث، طبیب، مصنف اور فقیہ
تھا.اس کے بیٹے عبد الملک (ابو مروان ابن زہر Avenzoar 1162ء) نے مشرق کے اسلامی ممالک میں جاکر
طلب کی اعلیٰ تعلیم حاصل کی تھی.ایک عرصہ مصر میں طبابت کے بعد وہ اندلس واپس لوٹا اور اشبیلیہ میں طبابت شروع
کی.جارج سارٹن نے اسے قرون وسطی اور اسلامی عہد کا عظیم ترین طبیب کہا ہے.ابومروان کے بعد اس کا بیٹا ابو بکر
ابن زہر (1199-1110ء) بھی کامیاب ادیب نغز گو شاعر، اور طبیب تھا.باپ کی زندگی میں وہ اس کے ہمراہ
امیر عبدالمومن کے شاہی دربار میں ملازم رہا اور اس کی وفات پر امیر عبد المومن نے اسے اپنا طبیب خاص مقرر کیا.طبانت اس خاندان کا چونسلوں تک موروئی پیشہ ہا اور کئی افراد خاندان خلفاء کے شاہی طبیب مقرر ہوئے.(5) دوستوں پر جان چھڑکتا تھا اور ارسطو کے اس مقولے کا صدق دل سے قائل تھا" ہر نئی چیز اچھی ہوتی
ہے مگر دوستی جتنی پرانی ہوائی ہی عمدہ اور مضبوط ہوتی ہے".شاعر نے کیا خوب کہا ہے:
اے ذوق کسی ہمدم دیر ینہ کا ملنا
بہتر ہے ملاقات مسیحا د خضر سے کی جب فنی زندگی شروع ہوئی تو سب سے پہلے اس کے نیاز مندانہ تعلقات طبیب حاذق ابومردان
ابن زہر (10921162 ء ) سے قائم ہوئے.دونوں میں اس قدر تعلق بڑھا کہ جب نے کلیات فی
حسب مکمل کی تو ابن زہر سے فرمائش کی کہ وہ بھی طب پر ایک کتاب لکھے تا کہ دونوں کی کتابیں اس فن پر
انسائیکلو پیڈیا قرار دی جائیں.چنانچہ نے کلیات میں کہا ہے:
میں نے اس تصنیف میں فن طب کے امور کلیہ کو جمع کر دیا ہے اور ایک ایک عضو
کے امراض کو الگ الگ بیان نہیں کیا ہے کیونکہ اس کی کچھ ضرورت بھی نہیں ہے.یہ
باتیں امور کلیہ سے مستند یا ہوتی ہیں لیکن جب کبھی مجھے ضروری امور سے فرصت ہوئی تو
8
Page 27
میں اس موضوع پر کچھ لکھنے کی کوشش کروں گا.فی الحال ابو مروان ابن زہر کی کتاب
التبسیر اس کے لئے کافی ہے جو میری فرمائش پر اس نے
قلم بند کی ہے."
طب میں ابن زہر کی کتاب التيسير في المداواة والتدبير' کے علاوہ دو اور مشہور کتابیں کتاب
الاغذيه ، اور کتاب الاقتصاد في اصلاح الانفس والاجساد ہیں.وو د نیا کا پہلا پیرا سائٹولوجسٹ
(parasitologist ) تھا.اس نے کتاب استیسیر میں خارش (Scabies) کی نشاندہی اور پہلی بار وجوہات بیان
کیں.فن طب میں اس کا قابل ذکر اضافہ دو قسم کے اور ام (inflammation) کی نشاندہی ہے:
اول الاورام التي تحدث في الاغشية الذي يقسم الصدرطولان یعنی:
tumors produced in the membrane that separates the length of the chest
دوم: الاورام في الاغشیتہ القلب یعنی: inflammation of the membrane of the heart اور ابو بکر ابن زہر میں نیاز مندانہ تعلقات کی تین وجوہات تھیں : ہم پیشہ ، ہم منصب اور قدیم خاندانی
تعلقات.دوستی کے رشتہ اخوت کو بہت اہمیت دیتا تھا.کہتا تھا کہ دوست کی طرف سے جو تکلیف پہنچتی ہے
وہ دشمن کی دی ہوئی تکلیف سے زیادہ سخت ہوتی ہے".(فصل المقال صفحہ 25)
ابو بکر ابن طفیل کی پیدائش بارہویں صدی کی ابتدا میں اور وفات 1185ء میں ہوئی.وہ بے مثل طبیب،
ریاضی داں ، اور خوش گو شاعر ہونے کے ساتھ فلسفے کی تمام شاخوں پر قدرت رکھتا تھا.اندلس کے محققین نے کثیر
تعداد میں اس کے آگے زانوئے تلمذ تہ کیا تھا.ارسطو کی کتابوں کی تشریح و تلخیص کا جو کام اندلس کے عظیم فلسفی اور
سائنس دال ابن باجہ نے شروع کیا تھا وہ ادھورا رہ گیا تھا.خلیفہ ابو یعقوب یوسف نے اس تحقیقی کام کو مکمل کرنے کی
خواہش کا اظہار ابن طفیل سے کیا مگر وہ پیرانہ سالی کی وجہ سے اس کام کو انجام نہیں دے سکتا تھا اس لئے اس نے یہ
مشکل علمی کام جیسے ابھرتے ہوئے نو جوان عالم کے سپرد کیا.ابن
بن طفیل نے طبعیات الہیات اور فلسفہ جیسے دقیق موضوعات پر خامہ فرسائی کی اور ایک رسالہ نٹس پر نیز دو
کتابیں طلب پر لکھیں.ابن طفیل اور کے درمیان علمی اور فلسفیانہ مسائل پر جو خط و کتابت ہوئی تھی اس کو بھی
اس
کی تصنیفات میں شمار کیا جاتا ہے لیکن اس کی تمام تصنیفات میں اس کی ایک کتاب جی بن یقطان کی وجہ سے اس
کا نام ہمیشہ کے لئے امر ہو گیا.اس کتاب نے تاریخی اور فلسفیانہ طور پر بہت مقبولیت حاصل کی.فرانسیسی ،
انگریزی ، جرمنی ، اسپینی ، ڈچ اور اردو میں اس کے لاتعداد تراجم شائع ہوئے.اس کتاب کا ایک عربی مطبوعہ نسخہ
9
Page 28
کنکشن (کینیڈا) کی پبلک لائبریری میں موجود ہے جو بیروت سے شائع ہوا تھا.اس کتاب کی تصنیف کا مقصد
بہت اعلی و اشرف تھا.مصنف کے نزدیک ایک ترقی یافتہ تمدن کے لئے صرف عقلی اور کشفی علوم کافی نہیں بلکہ اخلاقی
اور مذہبی علوم کی بھی ضرورت ہے.ابن طفیل نے اس کتاب کے ذریعے حکمت، طریقت، اور شریعت مینوں میں
مطابقت پیدا کرنے کی عمدہ کوشش کی ہے.جارج سائین کا کہنا ہے کہ ابن طفیل اور کے بغیر مغربی اسلام
باباش بہ فلسفہ کا صحرا ہوتا.اندلس کے ممتاز صوفی ، عہد ساز فقیہ اور فاضل مصنف شیخ الاکبر محی الدین ابن العربي 1240-1165ء)
سے بھی کے ذاتی تعلقات تھے.جب قرطبہ کا قاضی تھا تو اس نے ان سے ایک مرتبہ درخواست کی
کہ میں آپ سے تصوف کے چند مسائل پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں لیکن ابن العربی نے بحث کرنے سے انکار کیا.ابن
یشد کے انتقال پر ابن العربی ( عمر 23 سال ) بنفس نفیس اس کے جنازہ میں شریک ہوئے اور تجہیز و تکفین کے بعد
ان سال مشرق کے اسلامی ممالک کی سیاحت کے لئے روانہ ہوئے اور مراقش سے ہوتے ہوئے مصر پہنچے.تاریخ کی کتابوں میں ابن العربی اور کے درمیان خود ابن العربی کی زبانی ایک ملاقات کا حال اس
طرح بیان ہوا ہے میں نے وہ دن ابو ولید کے گھر قرطبہ میں گزارا.اس نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا
کہ وہ مجھ سے ملاقات کا متمنی ہے کیونکہ وہ میرے بعض الہامات من چکا تھا جو مجھ پر سکنج عزلت میں نازل ہوئے تھے
اور جن کو سن کر اس نے حیرت و استعجاب کا اظہار کیا تھا.چنانچہ اس بات کے پیش نظر میرے والد جو اس کے قریبی
دوستوں میں سے تھے کوئی تجارتی معاملہ طے کرنے کے بہانے مجھے اپنے ساتھ اس کے گھر لے گئے تا کہ وہ مجھ سے
متعارف ہو جائے.اس وقت میں بغیر ڈاڑھی کے نوجوان لڑکا تھا.جو نبی میں گھر میں داخل ہوا فلسفی اپنی جگہ سے میرا
خیر مقدم کرنے کے لئے محبانہ اور برادرانہ طور پر اٹھا اور مجھے سینے سے لگا لیا.پھر اس نے مجھ سے " ہاں" کہا اور
اطمینان کا اظہار کیا کہ میں اس کا مدعا سمجھ گیا ہوں.میں نے اس کے برعکس اس کی نیت جان کر کہ کیوں کر وہ خوش
ہوا، جو ایاً کہا " نہیں ".یہ سن کر مجھ سے ذرا ادھر ہو گیا ، اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور جو کچھ اس نے
میرے بارے میں سوچا تھا اس کے متعلق شک میں مبتلا ہو گیا.اب اس نے مجھے سے سوال کیا: تم نے الہام
اور عارفانہ تجلی سے کس عقد کیا حل تلاش کیا ہے؟ کیا یہ منقل و تدبر سے حاصل ہونے والے حل سے میل کھاتا ہے؟
میں نے جواب دیا کہ ہاں اور نہیں مثبت اور منفی کے درمیان مادہ کے ماوراء، روحیں پرواز کرتی ہیں، اور گرد میں اپنے
جسموں سے خود کو الگ کر لیتی ہیں.ین کر کا رنگ فق ہو گیا.میں نے اس کو تھر تھراتے دیکھا اور یہ فقرہ اس کے لبوں پر تھا لا غالب الا
الله.یہ اس لئے تھا کیونکہ وہ میرا اشارہ سمجھ گیا تھا.اس کے بعد اس نے میرے والد سے مجھ سے دو بار د ملنے کی
10
Page 29
خواہش کی تاکہ وہ مجھے بتلا سکے کہ میری بات کا جو مطلب تھا وہ اس نے سمجھ لیا تھا.وہ جاننا چاہتا تھا کہ جو اس نے سمجھا
آیا وہ وہی تھا جو میرے کلام کا مقصد تھا یا کچھ اور.وہ عقل سے کام لینے اور تدبر کرنے والے لوگوں میں رجل عظیم
تھا.وہ خدا کا شکر بجالایا کہ اسے اپنی زندگی میں ایک ایسے شخص کو دیکھنے کا موقعہ ملاجو گوشہ تنہائی میں جہالت کی حالت
میں داخل ہوا اور بغیر مطالعہ، بحث و مباحثہ اور تحقیقات کے کندن بن کر نکالا."
ابن العربی کی ایک اور ملاقات سے کشف کی حالت میں ہوئی: " ایک بار یک پرد: میرے اور اس
کے درمیان اس طرح تھا کہ میں تو اس کو دیکھ سکتا تھا مگر وہ مجھے نہیں دیکھ سکتا تھا، نیز وہ میری موجودگی سے بالکل
بے خبر تھا.وہ اس قدر منہمک تھا کہ اس نے میری طرف بالکل توجہ نہ کی اور میں نے اپنے آپ سے کہا کہ اس آدمی کا
اس راستہ پر قدم رنجہ ہونا مقدر نہیں جس پر میں گامزن ہوں." (6)
شاہی دربار سے تعلق کے نصیب کا ستارہ موحدین کی سلطنت میں بام عروج کو پہنچا.اس خاندان کا پہلا حکمران خلیفہ
عبد المومن بن علی تھا.اس نے بتیس سال (1163-1130ء ) حکومت کی.موحدین حکمرانوں میں وہ واحد فرمانروا
تھا جس نے فلسفیانہ علوم میں خاص دلچپسی کا عملی طور پر اظہار کیا.اس نے اپنے دربار میں اندلس کے عظیم المرتبت فلسفی
اور حکیم جیسے ابن باجہ ، مروان این زہر، ابن طفیل جمع کئے تھے.خلیفہ عبد المومن کے دربار میں کی رسائی کا قصہ اس طرح ہے کہ عبد المومن کی حکومت سے پہلے
اسکولوں کی عمارتیں خاص طور پر تعمیر نہیں کی جاتی تھیں بلکہ اندلس میں بچوں
کو تعلیم صرف مساجد میں دی جاتی
تھی لیکن عبد المومن نے تعلیم کو عام رواج دینے کے لئے مدارس قائم کرنے کا منصوبہ بنایا.اس تجویز کو عملی
جامہ پہنانے کے لئے اس کو چند منجھے ہوئے تعلیمی مشیروں کی ضرورت تھی جو خود عالم و فاضل ہونے کے ساتھ
ماہر تعلیم بھی ہوں.عبد المومن کی نظر انتخاب پر پڑی جو اس کی نظر میں اس اہم تجویز کو عملی جامہ
پہنانے کی اہمیت وصلاحیت رکھتا تھا.کو 1153 ء میں مراقش طلب کیا گیا.وہاں پہنچنے پر خلیفہ کو جب
اس کی محققانہ لیاقت علمی کمالات ، روشن خیالی ، وسعت علم اور وسیع النظری کا علم ہوا تو اسے شاہی دربار کے
خاص الخاص مصاحبوں اور مشیروں میں شامل کیا.عموماً اٹھارہ سال کے نوجوان کسی نہ کسی پیشے سے منسلک ہو جاتے ہیں.نے ابتدائی عمر میں کون سا
پیشہ اختیار کیا؟ تاریخ میں اس بارے میں کچھ نہیں ملتا.البتہ قرین قیاس ہے کہ چونکہ اس کے والد قرطبہ کے قاضی تھے
11
Page 30
اس لئے وہ بھی مقدمات لے کر ان کی عدالت میں حاضر ہوتا ہو.یہ بھی ممکن ہے کہ وہ قرطبہ کی شاہی لائبریری میں جس
میں چار لاکھ تا در کتا بیں تھیں کتابوں کے مطالعے میں وقت گزارتا ہو.کتابیں پڑھنے سے دماغ کو ہمیز لگتی ہے، جس کسی
کو ایک دفعہ مطالعے کا چسکا لگ جائے تو جب تک وہ کتاب یا رسالہ نہ پڑھ لے ، نشہ دور نہیں ہوتا.نیز کتابیں
علم و عرفان کا سر چشمہ ہوتی ہیں.بعض شواہد سے ظاہر ہوتا ہے کہ طب میں کا علم کتابی حد تک محمد د دتھا.علم وہ
دولت ہے جو خرچ ہونے سے بڑھتی ہے، خدا اس دولت میں برکت دیتا ہے جو مخلوق خدا کے لئے خرچ کی جائے.نے جب ستائیس سال کی عمر میں مرائش کا سفر کیا تو وہ اس وقت علم فلکیات کے بعض مسائل کی
تحقیقات میں مصروف تھا.وہاں پہنچ کر بھی ستارہ بینی اور مشاہدات فلکی کا سلسلہ برابر جاری رہا.اس بات کا ذکر اس
نے ارسطو کی ایک کتاب کی شرح میں کیا ہے.خلیفہ عبد المومن کا فلسفیانہ علوم کی طرف فطری رجحان تھا ، اس نے اپنے کتب خانے میں کثیر تعداد میں بیش
قیمت فلسفیانہ کتابیں جمع کی تھیں.اس کے دربار میں فلسفی حاضر رہتے تھے ان میں سب سے ممتاز ابن طفیل تھا.ابن طفیل ہی کی بدولت دیگر نامور فلاسفہ بھی وہاں جمع ہوئے.ایک روز خلیفہ عبد المومن نے فلسفیانہ مسائل پر گفتگو
کے دوران ابن طفیل سے کہا " ارسطو کا فلسفہ بہت دقیق ہے اور مترجمین نے عمدہ ترجمے نہیں کئے ہیں.کاش کوئی
شخص اس کا خلاصہ تیار کر کے اس کو قابل فہم بنائے ".ابن طفیل نے خلیفہ کی اس خواہش کا ذکر سے کیا اور
کہا میں بوڑھا ہو گیا ہوں، امیر المؤمنین کی خدمت سے فرصت نہیں ملتی، میں ایسا علمی کام نہیں کر سکوں گا مگر میں
خوب جانتا ہوں کہ تم اس کام کو بخوبی سر انجام دے سکتے ہو.ابن طفیل کی نگہ انتخاب جیسے قابل جو ہر پر
پڑی.دراصل اس نے میں چھپے گو ہر کو پہچان لیا تھا اس لئے اس نے اپنے قابل رفیق اور شاگرد کو اس
جانب توجہ دلائی اور فرمائش کی کہ چونکہ ارسطو کی جتنی شرمیں آج تک کی گئیں ہیں وہ سب کی سب مہم اور نا قابل فہم
ہیں اس لئے تم کو سیلمی خدمت انجام دینی چاہئے.اس علمی منصوبہ پر آمادہ ہوا اور اس نے ارسطو کی
کتابوں کی شرمیں لکھنی شروع کیں.خلیفہ عبد المومن نے جب 1163 ء میں اس دنیائے فانی سے کوچ کیا تو اس کا چھوٹا بھائی ابو یعقوب یوسف
سریر آرائے خلافت ہوا.یعقوب یوسف بلند حوصلہ خلیفہ اور بذات خود فاضل اجل تھا.وہ تیغ و قلم دونوں میدانوں
میں یکتائے زمانہ تھا.علوم عربیہ میں اس کا کوئی ہمسر نہ تھا.صحیح بخاری کے کئی حصے اس کی نوک زبان تھے.حافظ
قرآن ہونے کے علاوہ فقہ میں مہارت رکھتا تھا.طب میں بھی اس کو کمال حاصل تھا.فلسفہ کا اس کو خاص ذوق تھا.فلسفے کی کتابیں کثیر تعداد میں اس کی شاہی لائبریری کی زینت تھیں.12
Page 31
ابن طفیل خلیفہ ابو یعقوب کے دربار میں علمی مشیر ( سائینٹفک ایڈوائزر ) تھا.ابن طفیل نے شاہی دربار میں
فلسفہ کے ائمہ فن جمع کر رکھے تھے.اب تک کو فلسفیانہ حیثیت سے زیادہ شہرت حاصل نہ تھی لیکن ابو یعقوب
یوسف کے دربار میں پہنچ کر اس کی علمی حیثیت لوگوں پر بطور فلسفی عیاں ہوئی.نے یہ واقعہ اپنے ایک
شاگرد سے کچھ اس طرح بیان کیا جسے عبد الواحد مراقشی نے اپنی تصنیف' المعجب في تلخيص اخبار المغرب
میں رقم کیا ہے:
جب میں دربار میں داخل ہوا تو ابن طفیل وہاں حاضر تھا.اس نے امیر المومنین یوسف کے حضور مجھ کو پیش کیا
اور میرے خاندانی اعزاز ، میری ذاتی لیاقت اور میرے ذاتی اوصاف کو اس رنگ میں بیان کیا جس کا میں مستحق نہ
تھا.لیکن اس سے میرے ساتھ اس کی مخلصانہ محبت وعقیدت کا اظہار ہوتا تھا.پھر یوسف میری طرف مخاطب ہوا،
پہلے میرا نام و نسب پوچھا پھر فوراً یہ سوال کیا کہ حکما افلاک کے متعلق کیا رائے رکھتے ہیں؟ یعنی ان کے نزدیک عالم
کا ئنات قدیم ہے یا حادث؟ یہ سوال سن کر مجھ پر خوف کی حالت طاری ہوگئی اور میں نے بہانے تلاش کرنے شروع
کر دئے.میں نے عرض کیا کہ میں فلسفے سے واقف نہیں ہوں.خلیفہ یوسف میری بدحواسی کو تاڑ گیا اور ابن طفیل کو
مخاطب کر کے اس مسئلے پر گفتگو شروع کر دی اور ارسطو، افلاطون اور دیگر حکماے متقدمین نے جو کچھ اس مسئلے پر کہا
ہے اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا.پھر متکلمین اسلام نے حکما پر جو اعتراضات کئے ہیں وہ ایک ایک کر کے بیان
کئے.یہ دیکھ کر مجھ پر خوف کی جو حالت طاری تھی وہ ختم ہو گئی.لیکن مجھے تعجب ہوا کہ خلیفہ یعقوب یوسف علوم عقلیہ
میں اتنی دستگاہ رکھتا تھا جو طبقہ علما میں بھی شاذ و نادر کسی کو حاصل ہوتی ہے حالانکہ عالم اس قسم کی بحثوں میں اکثر مصروف
رہتے ہیں.اب یوسف نے میری طرف توجہ مبذول کی تو میں نے مکمل آزادی کے ساتھ اس موضوع پر اپنے
خیالات کا اظہار کیا.جب میں دربار سے رخصت ہونے لگا تو انہوں نے مجھ کو نقد مال، خلعت ، ایک گھوڑا اور بیش
قیمت گھڑی بطور انعام کے عطا کی." کا یہ کہنا کہ ابن طفیل نے میرے جو ذاتی اوصاف بیان کئے ان کا میں مستحق نہ تھا، در اصل کسر نفسی پر مبنی
تھا.ابن طفیل اس بات سے خوب واقف تھا کہ 1157ء سے 1163 ء تک ارسطو کی تقریباً نہیں کتابوں کے
جوامع لکھ چکا تھا.جیسے طبعیات، ما بعد الطبعیات اور منطق کا مجموعہ ( آرگانان ).پھر طلب پر اس کی محققانہ
تصنيف الكليات في الطب 1162ء میں منظر عام پر آچکی تھی.اس لئے ایک مسلمہ طبیب فلسفی اور شارح
ارسطو کی حیثیت سے اس کی شخصیت بہت ممتاز تھی.بعض مؤرخین کا خیال ہے کہ شاید خلیفہ ابو یعقوب یوسف سے ارسطو کے فلسفہ کی شرح و تلخیص اس
لئے کرانا چاہتا تھا تا کہ مغرب میں اس کو وہی فضیلت حاصل ہو جائے جو خلیفہ مامون الرشید کو مشرق میں حاصل تھی.13
1
I
Page 32
រ اور ابن طفیل میں گہرے دوستانہ مراسم تھے.ابن طفیل چونکہ گوہر شناس تھا اس لئے اس کی رسا عقل اور دور
اندیشی کے طفیل سے وہ علمی کارنامہ انجام پذیر ہوا جس کے باعث وہ تین صدیوں تک یورپ کے لاطینی
حلقوں میں آفتاب نیم روز کی طرح چمکتا رہا.ابن طفیل ابن باجہ کا شاگرد ہونے کے ساتھ اس کا مقلد بھی تھا.چنانچہ
اپنے فلسفیانہ ناول حي ابن يقظان میں ابن باجہ کی تصنیف کے تذکرے میں اس نے کا ذکر درج ذیل
الفاظ میں کیا ہے:
و اما من جاء بعدهم من المعاصرين لنا فهم بعد في حد التزايد والوقوف على غير
کمال او لمن لم تصل الينا حقيقه
ابن باجہ کے بعد جو فلاسفہ ہمارے معاصر ہیں وہ ابھی دور تکون میں ہیں اور کمال کو نہیں پہنچے ہیں اور اس بناء
پر ان کی اصلی قابلیت کا اندازہ ابھی نہیں ہو سکتا."
یہاں ہمارے معاصر " سے اشارہ کی طرف ہے.اسی حسن ظن کی بناء پر بن طفیل نے کی
یوسف بن عبد المومن کے دربار میں رسائی کرائی تھی.خلیفہ ابو یعقوب یوسف کے دربار میں پذیرائی اور قدرشناسی کے بعد کی دنیوی ترقی اور علمی فضیلت کا
دور شروع ہوا اور وہ شہرت کے پروں پر اڑنے لگا.جب اس کو 1169ء میں اشبیلیہ کا قاضی ( مجسٹریٹ ) مقرر کیا
گیا تو اس نے قرطبہ سے اشبیلیہ میں رہائش اختیار کی.شرح کتاب الحیوان کے چوتھے باب میں جو اس نے
اسی سال مکمل کی تھی اس نے قاضی کے فرائض بیان کئے ہیں، اور معذرت طلب کی ہے کہ اگر کتاب میں سہو و خطا ہو
گئی ہو تو معافی کا امید خواہ ہوں کیونکہ عہدہ قضا کی مصروفیتوں سے فراغت نہیں ملتی.نیز میرا کتب خانہ بھی قرطبہ میں
ہے اور حوالوں کے لئے مطلوبہ کتا میں اس وقت یہاں موجود نہیں ".وہ تین سال بعد یعنی 1172ء میں قرطبہ واپس
منتقل ہوا.غالباً اسی سال اس نے ارسطو کی کتابوں کی ایسی شرحیں لکھنی شروع کیں جو تنوع مضامین اور وسعت
معلومات کے پیش نظر شرح بسیط کہلاتی ہیں جبکہ اس سے پہلے کی لکھی گئیں شرحیں مختصر (epitome) ہوتی تھیں.کو جس قدر علمی شوق تھا اسی قدردہ کثیر الاشغال بھی تھا لیکن اس کثیر الاشغالی میں بھی تصنیف و تالیف کا
کام ہمہ وقت جاری رہتا تھا.علمی کاموں کے لئے دماغی سکون، ارتکاز اور نجی امور اور عائلی مسائل سے فرصت کی
ضرورت ہوتی ہے لیکن دربار سے تعلق اور عدالت کے قاضی ہونے کی وجہ سے وہ معمولات زندگی میں از حد مصروف
رہتا تھا.خود اس کی دلی خواہش تھی کہ دنیا کے کاموں سے فارغ ہو کر تمام وقت صرف اور صرف علمی کاموں میں
صرف کرے.لیکن ایسا ممکن نہ تھا.اپنی تصنیفات میں اس نے شکایت کی ہے کہ میں فرائض منصبی کے پیش نظر بہت
14
Page 33
مجبور ہوں ، اتنا وقت نہیں کہ تصانیف اور شرحوں کے کام سکون خاطر سے سرانجام دے سکوں.علم فلکیات کی مشہور و
معروف کتاب محسطی کی تلخیص میں اس نے لکھا ہے کہ میں نے صرف اہم مطالب لئے ہیں کیونکہ میری حالت بالکل
ایسے شخص جیسی ہے جس کے مکان میں آگ لگی ہو اور وہ اضطراب کی حالت میں مکان کی قیمتی اشیاء کو باہر نکال نکال
کر پھینک رہا ہو.عدالت کے کاموں کے سلسلے میں اس کو دور و نزدیک شہروں کے لیے لیے سفر بھی کرنے پڑتے
تھے، آج مرائش میں تو کل قرطبہ میں اور پھر افریقہ جیسے دور کے ملکوں کے سفر.لیکن اس دوران بھی ترجمہ و تالیف کا
سلسلہ جاری رہتا تھا.یادر ہے کہ دس سال تک (1182-1172ء ) وہ قرطبہ میں قاضی کے عہدے پر فائز رہا.کتاب البیان اور کتاب الا نھیات 1174ء میں دونوں اکھٹی لکھنا شروع کیں لیکن اس دوران صاحب
فراش ہو گیا، زندگی کی کوئی امید نہ رہی.اس خیال کے پیش نظر پہلی کتاب کو چھوڑ کر کتاب الالهیات کو مکمل کرنا
شروع کر دیا.1178ء میں اس کو مراقش کا سفر کرنا پڑا تو یہاں رسالہ جواهر الکون زیب قرطاس کیا.کچھ ماہ
بعد اس کو اشبیلیہ واپس آنا پڑا تو یہاں علم کلام میں دو جلیل القدر کتابیں یعنی فصل المقال اور کشف عن
مناهيج الادلة (1179ء) قلم بند کیں.1182ء میں ابن طفیل کی وفات کے بعد خلیفہ یوسف نے اس کو مراقش بلوا کر شاہی طبیب مقرر کیا.خلیفہ اس
کی خدمات سے اس قدر خوش تھا کہ اسی سال محمد بن مغیث کی رحلت پر اسے قاضی القضاۃ کے منصب پر فائز کیا.ایک طرف شاہی طبیب ہونے کے باعث اس کو مرافقش میں قیام کرنا پڑتا تھا تو دوسری طرف چیف جسٹس ہونے کے
باعث اندلس کے تمام اضلاع کا دورہ کرنا پڑتا تھا.یہ اس کی دنیوی ترقی میں آخری منصب تھا جس پر اس کے دادا اور
والد بھی سرفراز رہ چکے تھے.نو سال تک (1178-1169ء ) دو ارسطو کی کتابوں کی تلخیص اور شروح متوسط لکھتار با 1180-1174ء
کے دوران اس نے اپنی طبع زاد کتابیں لکھیں جیسے فصل المقال، كشف عـن الـمـنـاهيج اور تهافت
التهافة.اس کے بعد اس نے شروح بسیط ( تفاسیر لکھنی شروع کیں.خلیفہ ابو یعقوب یوسف کی وفات پر اس کا بیٹا یعقوب منصور ( 1199-1184ء ) تخت نشین ہوا.یہ نہایت
دین دار، عالم باعمل تھا.وہ پنج وقتہ نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کرتا تھا.اس کے دور خلافت میں موحدین کی
حکومت اپنے عروج پر پہنچ گئی.اس نے عیسائیوں کو شکست دے کر اندلس کے کھوئے ہوئے اضلاع واپس لئے بلکہ
ایک وقت میں تو ددان کے دارلخلافہ طلیطلہ (Toledo) پہنچ گیا.وہ فقہ وحدیث میں مہارت رکھتا تھا اس نے فقہاء
کو حکم دیا تھا کہ وہ کسی امام کی تقلید نہ کریں بلکہ خود اجتہاد سے فیصلے کریں.عدالتوں میں جو فیصلہ کیا جاتا تھا وہ قرآن،
15
Page 34
حدیث، اجماع اور قیاس کی روشنی میں کیا جاتا تھا.خلیفہ منصور نے بھی اپنے باپ کی طرح کی بہت قدردانی کی بلکہ اس کے عہد میں کو اپنی قدرد
منزلت حاصل ہوئی جتنی اس سے پہلے کسی اور کو حاصل نہیں ہوئی تھی.کو خلیفہ المنصور کی ندیمی کا بھی فخر
حاصل تھا کیونکہ خلیفہ فرصت کے اوقات میں اس کے ساتھ بے تکلف ہو کر علمی مسائل پر گفتگو کیا کرتا تھا.یہ بے تکلفی
اتنی بڑھ گئی کہ گفتگو کے دوران این رشد منصور کو اسمع یا اخی" کہہ کر مخاطب کرتا تھا.عمر کے آخری حصہ میں قرطبہ میں زیادہ وقت علمی مشاغل میں گزارتا تھا.1195ء میں خلیفہ منصور کو
اطلاع ملی کہ عیسائی بادشاہ الفانسو ختم (AlphonsoVIII) اندلس کے اسلامی علاقوں میں فساد ڈال کر مسلمانوں
کی بستیوں کو لوٹ رہا ہے.الفانسو کے مقابلہ کے لئے مہم پر جانے کے لئے قرطبہ سے روانہ ہونے سے
قبل اس نے کو بلوایا اور سر آنکھوں پر بٹھایا.قصر شاہی میں افسران حکومت کی جو نشست گا ہیں مقرر تھیں ان میں عبدالواحد
الي حفص جو خلیفہ منصور کا داماد اور ندیم خاص تھا اور جس کی کرسی تیسرے نمبر پر تھی اس سے بھی آگے بڑھ گیا
اور خلیفہ منصور نے اس کو اپنے پہلو میں جگہہ دی اور دوستانہ رنگ میں بے تکلفانہ باتیں کیں.جب شاہی
دربار سے باہر قدم رنجہ ہوا تو دوست احباب اس کے منتظر تھے، سب نے اس سرافرازی پر اس کو ہدیہ تبریک پیش کیا
لیکن نے کہا کہ یہ مبار کہار کا موقعہ نہیں کیونکہ امیر المومنین نے میری توقع سے بڑھ کر عزت افزائی کی ہے.شاید اس خاطر مدارت اور تقرب کا برا انجام ہو.یہاں اس کے اعداء بھی موجود تھے جنہوں نے شہر میں بے پر کی خبر
ازادی کہ امیر المومنین نے اس کے قتل کا حکم دیا ہے.اس لئے نے اپنے خادم سے کہا کہ وہ گھر میں جا کر کہہ
دے کہ اس کے گھر پہنچنے سے قبل بنی ، کبوتر بھون کر تیار رکھیں.اس امر میں یہ پیغام پنہاں تھا کہ اہل خانہ کو ان کی
خیر و عافیت کی اطلاع ہو جائے.خلیفہ سے کا یہ تقرب اور بے تکلفی ان کے دشمن اور سفلی حاسد ایک آنکھ نہ دیکھ پائے.جیسا کہ ابن
رشد نے خدشہ کا اظہار کیا تھا کہ شاید یہ تقرب برے نتائج پیدا کرے، بالکل ایسا ہی ہوا.حاسدوں نے خلیفہ منصور
سے اس کے طلحہ و بے دین ہونے کی شکایتیں کیں تا کہ اس کی نظر میں گر جائے.بالآخر وہ اپنے مقصد میں
کامیاب ہو گئے اور نے زندگی کے آخری چار سال ذلت ورسوائی کی حالت میں گزارے.خلیفہ نے اس کو
قرطبہ کے قریب یہودیوں کی بستی لوسینا (Licena) میں نظر بند کر دیا.کہتے ہیں کہ مصیبت سے زیادہ کوئی بڑا استاد
نہیں ہوتا، اس ابتلاء نے کی جی بھر کر تربیت کی.فی الحقیقت اس کی شخصیت کا نکھار آلام روزگار کابی مربون
منت تھا.16
Page 35
رسوائی کے اسباب
خلیفہ ابو يوسف يعقوب المنصور مطلق العنان بادشاہ تھا.جو لوگ شاہی دربار میں بارسوخ اور بادشاہ کے قریب
ہوتے تھے ان کی جان ہر وقت سولی پر چڑھی رہتی تھی کہ اگر بادشاہ کی نظر عنایت پھر گئی تو ان کی زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا.بادشاہ کسی اصول زندگی کے پابند نہیں ہوتے ، ان کے یہاں ہر وقت سازشیوں کا مجمع لگا رہتا تھا، ہر کوئی مطلب براری
کے لئے تگ ورد کرتا تھا.سازشیوں کا مقصد سلطنت کی حفاظت کے بجائے مذہب کی آڑ میں اپنے اعداء کو زک پہچانا
ہوتا تھا.اکثر لوگ سازش کی اصل غرض کو نہیں جان پاتے.اس حقیقت سے بخوبی با خبر تھا اس لئے اس نے کہا
تھا کہ یہ خوشی کا موقعہ نہیں بلکہ رنج کا موقعہ ہے کیونکہ یہ تقرب شاید برے نتائج پیدا کرے.خلیفہ منصور جس نے کی اس قدر عزت افزائی کی تھی وہی اس کی رسوائی کا باعث ہوا.یہ ایک دلفگار
واقعہ ہے اس لئے مورخین نے اس کے اسباب پر چھان بین اور تحقیق کے بعد جن وجوہات کو ممکن قرار دیادہ کچھ اس
طرح ہیں:
(1) علامہ ابن ابی اصیحہ نے طبقات الاطباء میں لکھا ہے کہ جب خلیفہ منصور کے دربار میں
جاتا تھا تو دونوں میں بے تکلفی کی وجہ سے کسی علمی مسئلہ پر بحث کے دوران وہ خلیفہ کو اسمع یا اخی کہ کر مخاطب
کرتا تھا.یہ بات خلیفہ منصور کے دل میں کھنکتی تھی.(2) خلیفہ ابو یوسف یعقوب (لقب منصور ) کا بھائی ابو یٹی جو قرطبہ کا گورنر تھا اس کے ساتھ کے
دوستانہ مراسم تھے.شاید ابوتیچی کے ساتھ اس کی بے تکلفی خلیفہ منصورکو ناگوار گزری ہو.یا یہ وجہ ہو کہ منصورا اپنے بھائی
سے ناراض
تھا اور نہیں چاہتا تھا کہ اس کا کوئی مقرب اس کے بھائی کے ساتھ میل جول رکھے.(3) ایک دفعہ قرطبہ کے منجمین نے پیش گوئی کی کہ فلاں دن ہوا کا ایک ایسا طوفان آئے گا کہ تمام لوگ ہلاک
ہو جائیں گے.اندلس میں یہ پیش گوئی جب زبان زد عام ہوئی تو عوام الناس اس قدر وحشت زدہ ہو گئے کہ گھروں
میں تہ خانے کھود لئے.قرطبہ کے گورنر نے شہر کے علما کو جن میں قاضی قرطبہ بھی شامل تھا، گورنر ہاؤس میں
بلوا کر اس موضوع پر گفتگو کی کہ ستاروں کے اثر کے تحت اس طوفان کے متعلق ان کی کیا رائے ہے ؟ گفتگو کے دوران
شیخ ابومحمد عبد الکبیر نے کہا کہ اگر ہوا کا یہ طوفان واقعی آ گیا تو قوم عاد کے بعد یہ دوسرا تباہ کن طوفان ہوگا.اس کی یہ
رائے سن کر سیخ پا ہو گیا اور کہا کہ خدا کی قسم قوم عاد کا کوئی وجود ہی نہ تھا.چونکہ یہ قرآن مجید کی آیت کریمہ
54:19 کا صریح انکار تھا اس لئے قاضی شہر کی یہ رائے سن کر محفل میں موجود علما چراغ پا ہو گئے.17
Page 36
(4) کے دشمنوں نے جو اس کی ہمسری کا دعویٰ رکھتے تھے منصور کی خدمت میں اس کی فلسفیانہ
کتابوں کے بعض اقتباسات پیش کئے.ایک کتاب میں کے ہاتھ کا لکھا بعض قدیم فلاسفہ کا یہ قول موجود تھا
کے نہ ہر ہ سیارہ دیوتا ہے.خلیفہ منصور نے کو دربار میں طلب کیا اور مذکورہ کتاب کو غصہ سے اس کے سامنے
پھینک کر پوچھا کیا یہ تمہاری تحریر ہے؟ نے تردید کی.اس پر خلیفہ منصور نے کہا اس تحریر کے لکھنے والے پر
خدا کی لعنت ہو اور تمام حاضرین سے کہا وہ بھی لعنت بھیجیں.اس کے بعد اس نے کو ذلت آمیز طریقے سے
رخصت کیا اور حکم جاری کر دیا کہ جو لوگ فلسفیانہ بحثوں میں مشغول ہیں ان کو فوراً جلا وطن کر دیا جائے.ایک اور
فرمان یہ بھی جاری کیا گیا کہ لوگ فلسفیانہ علوم کا مطالعہ بالکل ترک کر دیں، فلسفہ کی تمام کتابیں نذر آتش کر دی
جائیں.اس فرمان شاہی پر فوراً عمل کیا گیا اور کی فسفہ اور منطق کی کتابیں قرطبہ کے ایک بازار کے چوک
میں جلائی گئیں.یہ روایت شمس الدین ذہبی کی کتاب العبر میں موجود ہے.(5) نے جب ارسطو کی کتاب الحیوان کی شرح لکھی تو اس میں جملہ جانوروں کے ذکر میں زرافہ
کے متعلق لکھا کہ میں نے اس جانور کو شاد بربر ( ملک البربر، ذو معنی ہے بر بر قوم کا بادشاہ یا وحشیوں کا بادشاہ) یعنی منصور
کے باغ میں دیکھا ہے.یہ طریقہ خطاب خلیفہ منصور کی صریح تو ہین تھی امیر المومنین کے بجائے، خلیفہ منصور کو شاہ بر بر کا
خطاب ناگوار گزرا.نے صفائی پیش کی کہ پڑھنے والے نے اس لفظ کو غلط پڑھا ہے میں نے ملك البرين
لکھا ہے یعنی دو خطوں اسپین اور مراقش کا بادشاہ.یہ توضیح قابل قبول
سمجھی گئی.مگر اس کے دشمنوں نے اس پر الحاد اور
بے دینی کا جو الزام لگایا تھا اس کی بناء پر یہ معاملہ قومی اور مذہبی صورت اختیار کر گیا.منصور نے حکم دیا کہ مع
شاگردوں اور پیروکاروں کے مجمع عام میں حاضر کیا جائے.دربار کی جگہ کے لئے جامع مسجد قرطبہ کا انتخاب کیا گیا.خلیفہ نے اس غرض سے اشبیلیہ سے قرطبہ کا خاص سفر کیا.قرطبہ کی جامع مسجد میں ایک عام اجتماع ہوا جس میں بڑے
بڑے علماء اور فقہا شریک ہوئے اور پر فرد قرارداد جرم لگائی گئی.سب سے پہلے قاضی ابو عبد اللہ بن مروان نے
تقریر کی اور کہا کہ اکثر چیزوں میں نفع اور نقصان دونوں موجود ہوتے ہیں لیکن جب نفع کا پہلو نقصان کے پہلو پر غالب
آجاتا ہے تو اس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے ورنہ ایسی چیز ترک کر دی جاتی ہے.اس کے بعد خطیب مسجد ابو علی بن حجاج
نے فتوی دیا کہ ملحد اور بے دین ہو گیا ہے.اس کے بعد اور چند دیگر فضلاء ابو جعفر زاہی، ابوعبد الله محمد
بن ابراہیم قاضی ابوالربیع الكفيف ، ابو العباس، حافظ الشاعر القرابی کو قرطبہ سے کچھ دور لوسینا کی بستی اور دیگر مقامات
پر نظر بند کر دیا گیا.کچھ بھی ہو جو سلوک ماضی میں الکندی، ابن سینا اور ابن باجہ جیسے حکما زمانہ سے حکمرانوں نے کیا تھا
وہی سلوک سے روا رکھا گیا.یہ کا فروزندیق کا خطاب اس کے مرنے کے بعد بھی بہت مہنگا پڑا کیونکہ اسلامی
ممالک میں وہ گمنام رہا اور کسی نے اس کی تصنیفات عالیہ سے استفادہ نہ کیا.18
Page 37
مشہور مؤرخ انصاری کی روایت درج ذیل ہے:
" کی بربادی کا ایک سبب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے اپنی کتاب حیوان میں زرافہ کے ذکر میں لکھا
کہ میں نے اس جانور کو بر بر بادشاہ کے یہاں دیکھا ہے.یہ عبارت خود اس کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تھی منصور کو جب
اس کی اطلاع ہوئی تو وہ اس کے قتل پر آمادہ ہو گیا".خلیفہ منصور نہایت فخر پسند اور جاہ پسند تھا.لہذا یہ روایت قرین قیاس معلوم ہوتی ہے.اسے بڑی بڑی شاندار
عمارتیں بنوانے کا بہت شوق تھا.اشبیلیہ کی جامع مسجد کا بلند مینار فن تعمیر کا عمدہ نمونہ جواب جیرالڈا ٹاور ( Geralda
Tower) کہلاتا ہے اس کا تعمیر کردہ ہے.مراقش شہر کی قطبیہ مسجد کا دیدہ زیب مینار بھی اسی نے بنوایا تھا.ایک اور
واقعہ سے بھی اس سب کو تقویت ملتی ہے.1191ء میں جب صلیبی نوجوں نے یورپ سے شام اور فلسطین کی طرف
رخ کیا تو صلاح الدین ایوبی نے منصور سے فوجی مدد مانگی.خط میں صلاح الدین نے منصور کو امیرا المسلمین کے
خطاب سے مخاطب کیا تھا منصور کو یہ طرز خطاب ناگوار گزرا اور مدد دینے سے انکار کر دیا.صلاح الدین کا قصور صرف
یہ تھا کہ اس نے اس کو امیر المومنین تسلیم نہیں کیا لیکن نے تو اسے شاہ بر بر کہہ کر قیامت برپا کر لی، اس سے
زیادہ منصور کی تو ہین کیا ہو سکتی تھی.جس محفل میں خلیفہ منصور کو یہ اطلاع دی گئی اس میں کا دوست ابو عبد اللہ اصولی بھی موجود تھا.اس
نے کہا کہ پر غلط الزام لگایا گیا ہے دراصل اس نے لکھا ہے کہ میں نے اس جانور کو مسلك البرين (دونوں
ممالک، اندلس اور مراقش) کے بادشاہ کے یہاں دیکھا ہے.اصولی کی یہ دلیل اس وقت تو پسند کی گئی اور منصور اپنا
غصہ دیا گیا لیکن اس کے بعد جب گرفتار کیا گیا تو اس کے ساتھ ابو عبد الله اصولی کو بھی گرفتار کر کے لوسینا کی
بستی میں جلا وطن کر دیا گیا.(6) بعض کا کہنا ہے کہ جتنی روایتیں اوپر بیان ہوئی ہیں ان میں سے ایک بھی کی رسوائی کا سبب نہ
تھی بلکہ یہ وہ واقعات ہیں جو اس کی ذلت ورسوائی کے وقت ظہور پذیر ہوئے.اصل بات یہ ہے کہ خلیفہ منصور اس
وقت بادشاہ الفانسو ہشتم کے خلاف جہاد میں مصروف تھا.مالکی فقہ کے علما کا اس وقت ملک میں اثر ورسوخ بہت زیادہ
تھا.اسے علماء کی مکمل حمایت کی ضرورت کے علاوہ ملک کے اندر سیاسی استحکام کی بھی ضرورت تھی.علما کے سیاسی اثر
اور زور کا اندازہ کرتے ہوئے وقتی طور پر خلیفہ منصور نے یہ مناسب جانا کہ شاہی فرمان جاری کر دے کہ لوگ فلسفیانہ
علوم کی تعلیم کو ترک کر دیں اور ایسی تمام کتابیں نذر آتش کر دی جائیں.نیز علما کی آتش غضب کو کم کرنے کے لئے
چند فلسفیوں کو جلا وطن کر دیا.بہت ممکن ہے کہ خلیفہ کو یہ بات ناگوار گزری ہو کہ افسران حکومت اپنی ذمہ داریاں ادا کر
19
Page 38
نے کے بجائے فلسفہ کے مسائل سلجھانے میں مصروف ہیں.سرنا مس
آرنلڈ کا یہی نقطہ نظر ہے اور پروفیسر مائٹ گمری واٹے نے بھی اس امر کی تائید کی ہے کہ علمائے وقت
کا سیاسی اثر اس وقت ملک میں بہت گہرا تھا، وہ کہتے ہیں:
The Almohads had at times to make concessions in order to retain the
goodwill of the jurists is perhaps a pointer to the most serious weakness
of the Almohads - the lack of popular support.(7)
(7) ممتاز مورخ ابن خلدون نے خلیفہ منصور کے سلسلہ غزوات کو بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ وہ 1197ء
میں اشبیلیہ واپس آیا تو کے متعلق اس کی خدمت میں ایسے مقالے پیش کئے گئے جن سے اس کی بے دینی
اور بد عقیدگی ثابت ہوتی تھی.ان میں بعض مقالے خود اس کے اپنے ہاتھ کے لکھے ہوئے تھے اس لئے منصور نے
اس کو قید کر دیا ( ابن خلدون، کتاب العبر، جلد ششم صفحه 245)
(8) کے فرانسیسی سوانح نگار ارنسٹ رینان کی رائے میں خاندان بنورشد کے لوگ اپنے اندلسی
ہونے پر فخر کرتے تھے اور مشرقی عربوں کو نیچی نگاہ سے دیکھتے تھے.ان کے نزدیک اندلسی عربوں میں ارفع
خصوصیت یہ تھی کہ انہوں نے عرب اور بر بر اقوام کی تہذیب اور اعلیٰ اقدار کو اپنا کر اندلس کی علمی فضاء کو مزید تقویت
دی.اس امر کا ذکر نے افلاطون کی کتاب جمہوریہ کی شرح (1194ء) میں کیا تھا.اس دور میں بھی آج کی
طرح حکمراں طبقہ اشراف پر تنقید کرنا گویا آبیل مجھے مار کے مترادف تھا.بہر حال رینان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ ابن
رشد کی نظر بندی کا سبب قطعی طور پر سیاسی نوعیت کا تھا.خلیفہ منصور کا شاہی فرمان
خلیفہ منصور کے شاہی فرمان کو اس کے کا تب (سکریٹری ) ابو عبد اللہ ابن عیاش نے نہایت معلمی و سمع عبارت
میں لکھا تھا جس کا خلاصہ درج ذیل ہے : " قدیم زمانے میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے تھے جو وہم کے پیروکار تھے.لیکن ان کی عقل کے کمال کی وجہ سے عوام ان کے گرویدہ ہو گئے.ان لوگوں نے ایسی کتابیں لکھیں جو شریعت سے
اس قدر دور تھیں جس قدر مشرق و مغرب میں دوری ہے.ان لوگوں ( فلاسفہ ) کی تقلید میں اسلام میں بھی ایسے لوگ
پیدا ہو گئے جو اہل کتاب سے زیادہ نقصان دہ تھے.ان کے علم کا زہر ملک میں پھیلنے لگا تو ہم نے ایک مدت تک
تعرض نہیں کیا لیکن اس سے ان کی ہمت اور بڑھ گئی.آخر کار ہمیں ان کی چند ایسی ذلت آمیز کتابیں میں جو بظاہر
20
Page 39
قرآن مجید کی آیات سے آراستہ تھیں لیکن ان کا باطن الحاد سے بھرا ہوا تھا.ایسے لوگ وضع قطع ، زبان اور ظاہر طور پر تو
مسلمان تھے لیکن ان کا باطن مسلمانوں سے مختلف تھا.جب ہمیں ان کی خلاف شریعت با تیں معلوم ہوئیں تو ہم نے
ان کو دربار سے نکال دیا، ان کے جلاوطن کئے جانے کا حکم جاری کیا ، ان کی کتابیں جلوا دیں کیونکہ ہم مسلمانوں کو ان
کے قریب سے دور رکھنا چاہتے ہیں.اے میری رعایا ایسے لوگوں کے گروہ سے اس طرح خوف کھاؤ جس طرح لوگ
زہر سے ڈرتے ہیں.جو شخص ان کی کتابوں کو کہیں دیکھے ان کو آگ میں ڈال دے.اے خدا ہمارے ملک کو ملحدوں
کے فتنہ سے محفوظ رکھ اور ہمارے دلوں کو کفر کی آلودگی سے پاک کر.آمین"
خلیفہ منصور نے اس فرمان کے بعد فلسفہ، منطق اور حکمت کی کتابوں کو نذر آتش کئے جانے کا انتظام کیا اور یہ
اہم ذمہ داری مفید ابو بکر بن زہر کے سپرد کی.منطق و حکمت کی تعلیم پر قدغن لگا دیا گیا.اگر کوئی ان کے مطالعہ میں
مشغول پایا جاتا تو مورد سز ا نھیر تا.کتب فروشوں نے منطق و فلسفہ کی کتابیں اکھٹی کرنی شروع کر دیں اور جلد ہی
اندلس ایسی کتابوں سے صاف ہو گیا.یادر ہے کہ اس سے پہلے 1106 ء میں بھی فلسفہ کی کتابوں کو اندلس میں جلایا
گیا تھا.معلم ریاضی اور علم ہیئت کی کتابیں اس حکم سے مستشنی تھیں کیونکہ اسلامی رسومات و عبادات بشمول سمت قبلہ کے
تعیین میں ان علوم کی ضرورت پڑتی تھی.جلاوطنی کے تین برسوں میں پر کیا بیتی؟ قفس میں ان کے کیا مشاغل تھے؟ نظر بندی کے دوران ان
کی دماغی حالت کیسی رہی؟ کیا تصنیف و تالیف کا شغل جاری رہا؟ ان امور کی تفصیل کتابوں میں زیادہ نہیں ملتی لیکن
اتنا ضرور پتہ چلتا ہے کہ جلا وطنی کے زمانے میں ان کو بہت مصائب جھیلنے پڑے.بعض کا کہنا ہے کہ لوسینا
کی بستی سے فاس بھاگ گئے وہاں لوگوں نے ان کو پکڑ کر جامع مسجد کے دروازے پر کھڑا کر دیا تا کہ جو لوگ مسجد کے
اندر جائیں یا باہر نکلیں وہ ان پر تھوکتے جائیں.ان کا سماجی بائیکاٹ کیا گیا کوئی شخص ان سے ملاقات نہیں کر سکتا
تھا.عوام نے ان کو نشانہ تضحیک بنایا.مؤرخ انصاری نے ابوالحسن ابن قطرال کی روایت سے ایک واقعہ درج کیا ہے
جو کا بیان کردہ ہے:
حدثنا ابو الحسن بن قطرال عن انه قال اعظم ما طراعلى في التلبة اني
دخلت آن و ولدى عبد الله مسجد القرطبة ما قد حانت صلوة العصر فتار لنا بعض سفلة
العاملة فاخرجنا منه
( ترجمہ ) اس زمانہ میں سب سے زیادہ تکلیف مجھے اس وقت ہوئی جب میں اور میرا بینا عبد اللہ دونوں قرطبہ
کی ایک مسجد میں نماز عصر ادا کرنے کے لئے گئے تو لفنگوں نے ہمیں شور و غل بر پا کر کے مسجد سے نکال دیا.21
Page 40
بہر حال کے دشمنوں کو برا بھلا کہنے کا موقع نصیب ہو گیا تھا.شعراء نے طنز آمیز اشعار لکھے.ان
شعراء میں سے مشہور سیاح ابن جبیر اندلسی (مصنف رحلہ ) کے چند اشعار یہاں نقل کئے جاتے ہیں :
الآن قد ایقن ان توالیف
توالف
اب تو کو یقین آگیا کہ اس کی تالیفات تلف ہو گئیں
یا ظالماً نفسه تامل
هل تجد اليوم من توالف
اے وہ شخص جس نے اپنے او پر ظلم کیا غور کر کہا تو کسی کو اپنا دوست پاتا ہے
لم تلزم الرشد با بن رشد لما علا في الزمان جدك
اے جب تیر از مانہ تھا تو تو نے رشد و ہدایت کی پابندی نہیں کی
و كنت في الدین ذراء يا ما هكذا كان فيه جدك
تو نے مذہب کے متعلق ریا کارانہ طریقہ اپنایا تیرے دادا کا یہ طریق نہ تھا
نفذ القضا با خذ كل ممده متفلسف في دينه متزندق
تقدیر نے ہر طمع ساز فلسفی کو مذہب سے ملانے والے زندیق کو گرفتار کرا دیا
بالمنطق اشتغلو فقيل حقيقه ان البلاء مركل بالمنطق
وہ منطق میں مشغول ہوا اور یہ بات سچ ثابت ہوئی کہ مصیبت کی جڑ منطق ہے
ایک اور شاعر نے یوں طبع آزمائی کی:
بلغت امیر الؤمنین می المنى لانك قد بلغتنا ما تؤمل
قصدت الى الاسلام تعلى مناره ومقصدك الا سنى لدى الله يقبل
تدارکت دين الله في اخذ فرقة بمنطقهم كان البلاء المؤكل
آثار و على الدين الحنيفي فتنة لها نارغي في العقائد تشعل
اقمتهم للناس يبراء منهم
واوعزت في الاقطار با لبحث عنهم
وقد كان للسيف اشتياق لهم
ووجه الهدى من خزيهم بتهلل
وعن كتبهم والسعي في ذالك اجمل
ولكن مقام الخزي للنفس اقتل
22
Page 41
ایک اور شاعر کے طنز کے تیر ملاحظہ ہوں:
خليفة
الله انت
حقا
فارق من السعد خير مرق
حمتیم
الدين من عداه
وكل من رام فيه
فتقا
اطلعك
تفسلوا
الله سر قوم
وادعو اعلوما
حقو العضا با النفاق شقا
صاحبها
في المعاد يسقى
واحتقر والشرع وازدروه
سفاهة
منهم
و حمقا
او سعتهم لعنة و خزیا
وقلت
بعد الهم وسحقا
فابق الدين الا له كهفا
فانه
ما بقيت
يبقى تین سال یعنی 1195 کے 1197ء تک زیر عتاب رہا.بعض مورخین کا کہنا ہے کہ اشبیلیہ واپس آکر
جب خلیفہ منصور کو کے بڑھاپے کی عمر میں ذلت ورسوائی کا حال معلوم ہوا تو اس شرط پر رہا کرنے کا وعدہ کیا
کہ مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر اعلانیہ طور پر غلطی کا اعتراف اور توبہ کرے.چنانچہ نے اس شرط کو مان
لیا اور اسے مسجد لایا گیا ، جب تک لوگ نماز ادار کرتے رہے وہ بر ہنہ سر دروازے پر کھڑا رہا.سر پر پگڑی کے بغیر کھڑا
ہونا سخت تذلیل کا باعث تھا.کہاں قاضی القضاۃ اور کہاں یہ حالت زار.رہائی اور رحلت
روایت ہے کہ اشبیلیہ شہر کے سرکردہ افراد نے شہادت دی کہ پر بے دینی کا جو الزام عائد کیا گیادہ
سراسر غلط ہے.منصور نے ان شہادتوں کو قبول کر لیا اور سمیت اس کے تمام رفتاء کو 1197ء میں رہا کر دیا.ان میں سے ابو جعفر ذہبی کی خاص طور پر عزت افزائی کی اور اس کو طلبہ اور اطباء کا انسپکٹر مقرر کیا.خلیفہ منصور اس کے
بارے میں کہا کرتا تھا کہ ابو جعفر خالص سونے کے مثل ہے پگھلانے سے اس کا جو ہر اور زیادہ نمایاں ہو گیا ہے.ابن
رشد رہا ہونے کے بعد آزادی کے ساتھ رہنے لگا، زیادہ وقت تصنیف و تالیف میں گزرتا.قاضی کا عہدہ چونکہ بحال
نہیں ہوا تھا اس لئے مستقل آمدنی کے بغیر معاش کا کوئی اور ذریعہ نہ تھا.اس دوران ملک کے سیاسی حالات بہتر ہونے لگے.عیسائیوں کے بادشاہ نے خلیفہ منصور کو پیغام مصالحت
بھیجا.پانچ سال مسلسل جنگوں میں برسر پیکار رہنے سے فریقین تھک چکے تھے.خلیفہ منصور نے پیغام مصالحت سن کر
چین کا سانس لیا اور دست صلح بڑھا دیا.1196ء میں اس نے مراقش کا رخ کیا.یہاں کے قاضی کے خلاف
اس کو شکایتیں پہنچیں.خلیفہ بھی شاید حیلہ تلاش کر رہا تھا اس نے فوراً قاضی کو برطرف کر کے کا تقرر کر دیا.23
Page 42
کو جب یہ خبر ملی وہ پاؤں سر پر رکھ کر مراقش روانہ ہوا.فلسفہ کی کتابوں کو تلف کرنے کے جو احکامات جاری
کئے گئے تھے وہ منسوخ کر دئے گئے.خلیفہ منصور خود فلسفہ کی ترویج میں اس سیاسی شورش سے پہلے کی طرح منہمک
ہو گیا.خلیفہ پر یہ حقیقت عیاں ہو گئی تھی کہ اس سیاسی سازش کے در پردہ کے حاسدوں اور چند شر پسند علما
کی کوئی اور غرض تھی.یہاں مراقش میں ایک سال تک نے قضاء کے فرائض سر انجام دئے.مفلسی میں جو
دن گزارے تھے ان کا ازالہ ہونے لگا، ایک بار پھر وہ معاشرہ میں عزت کی نگاہوں سے دیکھے جانے لگا اور ، خلیفہ
منصور کا ایک بار پھر وہ مقرب اور مصاحب بن گیا.اچھے، پر لطف دونوں کی یاد تاز و ہونے لگی اور دوست احباب
نے سینہ سے لگا لیا.دسمبر کے مہینہ میں صاحب فراش ہوا، بیماری کی نوعیت کچھ ایسی تھی کہ موت کے بے رحم ہاتھوں کے
آگے بے بس ہو گیا.کچھ عرصہ بستر علالت پر گزارنے کے بعد مراقش میں جمعرات کے روز 10 دسمبر 1198ء جان
جان آفریں کے سپرد کر دی.شہر سے باہر باب تاغزوت کے قبرستان میں چشم پر نم کے ساتھ دوست احباب نے
اندلس کے اس مایہ ناز فرزند کو سپرد خاک کیا.یہاں وہ تین ماہ تک پیوند خاک رہا.پھر اس کے بیٹوں یا کسی رشتہ دار
کی خواہش پر اس کا جسد خاکی قرطبہ منتقل کیا گیا اور دوسری بار آبائی قبرستان مقبرہ ابن عباس میں آباء واجداد کے گنبد
میں اس کی تدفین ہوئی.ارض اندلس کا ی فلسفی شہزادہ اب بھی اسی جگہہ منوں مٹی تلے آرام کی نیند سو رہا ہے.خدا اس
کی تربت کو ہمیشہ نور سے بھرے اور آسماں سدا اس کی لحد پر شبنم افشانی کرتار ہے.سب کہاں کچھ لالہ وگل میں نمایاں ہو گئیں خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں
ی دنیا کی پرانی ریت ہے کہ جب کوئی مرجاتا ہے تو لوگ اس کو فراموش کر دیتے ہیں.دنیا موت وزیست
کیا تماشہ گاہ ہے، جو بھی پیدا ہوتا ہے وہ اپنی عمر بسر کر کے عالم فانی سے عالم جاودانی کی طرف روانہ ہو جاتا ہے
اور کچھ مدت بعد لوگ اسے فراموش کر دیتے ہیں.مگر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص مرکز ہمیشہ ہمیش کے
لئے زندہ ہو جاتا ہے.ایسے لوگ صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں.ایسے لوگ روشنی کا مینار ہوتے ہیں جو لوگوں
کو صحیح
راہ عمل دکھاتے ہیں :
لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے اور ابن العربی
محی الدین ابن العربی ، جو کی وفات کے فورا بعد مشرق کے اسلامی ممالک کے سفر پر روانہ ہوئے
24
Page 43
تھے، کا بیان ہے کہ مراکش میں میں نے خود دیکھا کہ کی لاش قرطبہ لے جانے کے لئے سواری پر رکھی جا
رہی ہے.کی وفات کے چند ہفتوں بعد خلیفہ منشور بھی 2 جنوری 1199 ، کو دنیا سے رخصت ہو گیا.ابن
بیطار نے بھی جو اندلس میں علم نباتات کا بہت بڑا عالم اور مصنف تھا اسی سال وفات پائی.اس سے اگلے سال حفید
ابو بکر ابن زہر جو کا جگری دوست اور خلیفہ منصور کے دربار میں اس کا ہم منصب تھا، فوت ہوا.ابومروان
بن زہر جس نے کی فرمائش پر کتاب التیسیو زیب قرطاس کی تھی.اور طب میں گویا اس کا استاد تھا وہ بھی
وفات پاچکا تھا.اس طرح ارض اندلس ان یکتائے روزگار انسانوں سے مختصر عرصہ میں محروم ہوگئی.یہ لوگ جو اپنے
علمی نور سے اندلس کو منور کرتے رہے ان کی روشنی ماند پڑنے سے ملک کے اندر جہالت کا اندھیرا چھانے لگا.مگر
ان قد آور اندلسی عالموں کے طفیل اندلس کی ضیا پاشیوں سے یورپ جگمگا اٹھا.یورپ والوں کے لئے مینارہ نور تھا مگر اپنے بیگانے بن گئے.فی الحقیقت اس کی موت سے پورا عالم اسلام انحطاط کا شکار ہو گیا کیونکہ
رواداری اور عقل پر پہرے بنھا دئے گئے.سائنس جو بھی مسلمانوں کی لونڈی تھی اب اس کے ذریعہ یورپ نے
مادی ترقی حاصل کرنا شروع کر دی.اس ترقی کے بیچ مسلمانوں نے ہی ہوئے تھے.اس دلچسپ داستان کی تفصیل
اگلے صفحات پر آئے گی.اولاد کو خدا نے حفظ مراتب سے آشنا ، رشتہ داروں سے محبت ، خلوص، اور تواضع سے برتاؤ کرنے والے
کئی بیٹوں سے نوازا تھا مگر ان میں سے دو نے خاص شہرت حاصل کی.بڑے بیٹے کا نام احمد اور کنیت ابوالقاسم
تھی.اس نے فقہ وحدیث کی تعلیم اپنے والد اور ابو القاسم ابن بشکوال سے حاصل کی.وہ حافظ حدیث ہونے کے
ساتھ روشن خیال دانشور تھا.فقہ اور اصول فقہ میں مہارت کی بناء پر قاضی کے عہدہ پر فائز ہوا.اس اہم عہدے کی
ذمہ داریاں اس نے تمام عمر نہایت دیانت داری سے سر انجام دیں.1225ء میں اس دنیائے فانی سے کوچ کیا.دوسرے بیٹے کا نام محمد اور کنیت ابو عبد اللہ تھی.اس نے طب کی تعلیم حاصل کی اور منصور کے بیٹے خلیفہ محمد ابن
یعقوب الناصر 1213-1199ء کے دربار میں شاہی طبیب کے عہدے پر فائز رہا.اس کی ایک کتاب کا نام
حيلة البر ہے.شخصیت، سیرت و اخلاق
یگانه روزگار، جامع کمالات علامہ کی زندگی پر غائرانہ نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بے حد محنتی ،
25
Page 44
اولوالعزم، با ہمت پیکر متانت اور بارعب شخص تھا.کم سخن ہونے کے باعث صرف ضرورت کے وقت گفتگو کرتا تھا.گفتگو بھی اس قدر محبت بھرے لہجے میں کہ گویا منہ سے پھول جھڑتے ہوں.سادہ، منکسر، متواضع اور دوسروں کے
کام آنے والے خدمت کو حصہ ایمان سمجھتے ہیں.اتنی جاہ و حشمت حاصل ہونے کے باوجود خاکساری و عاجزی اس
میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی.دولت ، شہرت، اور اہمیت نے اس کو جامہ سے باہر نہیں کیا.اگر چہ اسے شاہی دربار
میں اتنا اونچا عہدہ ملا ہوا تھا لیکن باوجود اس کے نہ تو مال و دولت جمع کیا اور نہ ہی کسی رشتے دار کو اپنے رتبے سے فائدہ
پہنچایا.جو کچھ مالی منفعت اس کو حاصل ہوئی اس سے دوسروں نے زیادہ فائدہ اٹھایا.حاجت روائی اور ضرورت
مندوں کی ضرورتیں پوری کرنا و داپنا فرض سمجھتا تھا.نے فقہ، فلسفہ علم فلکیات ، طب تفسیر جیسے علوم میں اپنی ذہانت، ذکاوت سلیم الطبعی ، عزم صمیم،
دیانت، اصول پسندی کا لوہا منوایا.خود پسندی ، عیش کوشی ، زردیدگی، جاہ طلبی ، مطلب پرستی کے پیتے ہوئے صحرا میں
اصول پرستی ، قناعت، دیانت اور صداقت کے ایسے پھول کھلائے جن کی خوشبو سے آج بھی مشام جاں معطر ہے.اس کے وجدان نے وہ چراغ روشن کئے جن کی روشنی آج بھی دنیا کو منور کر رہی ہے.مادی زندگی، کسب زر، جلب منفعت کو متاع حیات نہیں جانتا تھا.وہ روحانی اقدار کو زندگی کی معراج
گردانتا تھا.چاپلوسی سے سخت نفرت کرتا تھا ، بڑھاپے میں اتنی ذلت و رسوائی برداشت کی ، جلا وطن ہوا، مفلسی میں
وقت گزارا مگر کیا مجال کہ کسی کے آگے دست سوال دراز کیا ہو.مشکلات اور تنگ دستی کو صبر، قناعت اور وقارت
برداشت کیا.بادشاہ جسے ایک وقت میں برادر من کہہ کر مخاطب کرتا تھا بر افروختہ ہوا اور نظر بند کر دیا مگر پائے
استقامت میں لغزش نہ آئی.اپنے موقف پر چٹان کی طرح ڈٹا رہا تا آنکہ بادشاہ کو غلطی کا احساس ہوا اور خود بلا کر
دوبارہ قاضی کا عہد و پیش کیا.نا خوشگوار حالات کے باوجود مزاج میں کمی پیدا نہیں ہوئی ، زندگی کے ہر زیرو بم کا مقابلہ
خندہ پیشانی سے کیا.استقلال اور ایثار اس کی شخصیت کے عناصر ترکیبی تھے.وہ صبر وقناعت کا چلتا پھرتا مجسمہ تھا.نام و نمود حاصل کرنے یا محبوب خلائق بننے کی کوئی آرزو نہ تھی.اسے عربی کے مایہ ناز نا قد ، خوش فکر شاعر، ژرف نگاه محقق، اور صاحب فکر ادیب کا مرتبہ حاصل تھا.اس کا شمار
اندلس کی نابغہ روزگار ہستیوں میں ہوتا تھا.علم اس کی زندگی تحقیق اس
کی تسکین ، اور تخلیق اس کی مجبوری تھی.ایسی
مجبوری جو عام آدمی کو فنکار کی صف میں لا کھڑا کرتی ہے.اس مجبوری نے اسے لائق احترام اور معتبر ہستی بنا دیا تھا.حقیقت یہ ہے کہ علم سے فکر سے ، ادب سے آگہی اور دید دو دانش سے رشتہ استوار رکھنا بڑی سعادت ہے.لیکن یہ
سعادت کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے.وہ علم سے وابستگی کا روشن مینار تھا.اسے حرف سے لفظ سے، اور کتاب سے
عشق تھا اور اس عشق نے اسے ہمیشہ سرشار پر عزم اور فعال رکھا.اس کا گھر صاحبان فکر ، حاملان ذوق سلیم اور
26
Page 45
جویان علم کے لئے ایک مرکز تھا اور اس کی ژرف نگاہی ، اصالت فکر کا ایک زمانہ معترف تھا.ہم نے بیان کیا کہ وہ گہری نظر رکھنے والا حق تھا، تو محقق کون ہوتا ہے؟ محقق ذہنی کارنامے انجام دینے والے،
رازوں سے حجابات اٹھانے والے موضوع کی عظمت کو اجاگر کرنے والے ہعلمیت، معلومات ، جودت طبع ، وجدان
اور ذوق سلیم رکھنے والے کو کہتے ہیں.محقق کے لئے علوم و خون میں مہارت ، عصبیت سے دوری اور وسعت نظر رکھنا
لازمی ہے.اس
کی تحقیق میں تناسب ضروری ہے یعنی نفس مضمون اور موضوع میں مطابقت ہو.محقق وہ ہے جو سمندر
کی تہ سے لولوئے بے بہا نکال کر لاتا ہے.خوش ذوقی، غیر جانبداری، اور صداقت ایک اچھے حق کے اوصاف
ہیں.علم اور تحقیق کا چولی دامن کا ساتھ ہے کیونکہ تحقیق سے ترقی کا عمل آگے بڑھتا ہے.اچھا نقاد بھی تھا.تنقید ایسے تبصرے کو کہتے ہیں جو تخلیقی کارناموں کو پر کچھ کر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی
کر دے.تنقید تخلیقات
کو صحیح سمت میں لے جانے میں معاون ثابت ہوتی ہے.تخلیق اور تنقید دو بہنوں کی طرح
ہیں.ایک اچھا نقاد ہر تخلیق کا مطالعہ کر کے اس کے حسن و معائب سے آگاہ کرتا ہے.ایک دیو پیکر شخصیت ہونے کے ساتھ کثیر الجہت بھی تھا.فقہ، طب، ہئیت اور شروح ارسطو کے سلسلے
میں اس کے کارنامے سنہرے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہیں.متجسانہ ذہن جو فطری طور پر ودیعت کیا گیا تھا
اسے کائنات کے حقائق سے پردے اٹھانے پر اکساتا رہتا تھا.عالم اسلام میں وہ سب سے پہلا عقلیت پسند
(Rationalist ) تھا.عقلیت اور اجتہاد کی خشت اول اس نے پہلے رکھی گوہ علم ومعرفت کے حصول کو محض عقل کا
مرہون منت خیال نہیں کرتا تھا اور عقل کی قطعیت کا قائل نہ تھا لیکن عقل کی افادیت سے انکار بھی نہیں کرتا تھا.اس
کے نزدیک عقل اور شریعت ( الہام) کا اپنا اپنا دائرہ کار تھا.یورپ کے فلاسفہ کی عقلیت سیکولر تھی لیکن کی
عقلیت وحی والہام کے تابع تھی.اس کے نزدیک شرع اور عقل میں تناقض نہیں ہے
، عقل بغیر شرع کے بیکار اور شرع
عقل کے بغیر اپنا مقصود حاصل نہیں کر سکتی.عقل کو چشم بیٹا کی طرح اور شریعت کو آفتاب کے مانند خیال کرنا چاہئے،
آنکھ جس طرح سورج کی روشنی نہ ہونے سے بیکار ہوتی ہے اسی طرح عقل بغیر شرع کے بیکار ہے.نے اپنی فکری صلاحیت کی روشنی میں جو اجتہادات کئے و قابل ستائش ہیں.انہی اجتہادات نے ایک
نے طریق فکر کی داغ بیل ڈالی جس کی اتباع میں آنے والے دانشوروں نے نئے چراغ روشن کئے.علاوہ ازیں ارسطو
کی کتابوں کی ہمہ گیر اور مفصل تفاسیر لکھنے کی بناء پر وہ شارح اعظم (The Great Commentato) بھی تھا.آج کے جدید دور میں کسی کی اسلام میں اجتہاد کی بات کرنی ہو تو سب سے پہلے اس کی شخصیت ذہن میں ابھرتی
ہے.میرے نزدیک تو وہ مجتہد اعظم تھا.میں نے انٹرنیٹ پر اس کی جو تصاویر ( یعنی پینٹنگ، کیونکہ اس زمانے میں
27
Page 46
تصاویر
نہیں ہوتی تھیں) دیکھی ہیں ان کے مطابق اس کے چہرے سے ذکاوت، فطانت ، تابانی اور تازگی چڑھتے
سورج کی کرنوں کی مانند پھوٹتی نظر آتی ہے.چہرہ رعب دار جس پر بادشاہوں والا وقار اور جلال تھا.خدو خال سیکھے
تھے.آنکھیں روشن، ابرو کمان کی طرح تھی.بھاری جسم پر جبہ زیب تن کرتا تھا.ایک تصویر میں جو چغہ پہنے ہوئے
دکھایا گیا ہے اس پر لا غالب الا اللہ لکھا ہوا نظر آتا ہے.سر پر ہمیشہ پگڑی باندھتا تھا.داڑھی ترشی ہوئی ہوتی
تھی.بائیں ہاتھ میں ہمیشہ کتاب تھا مے ہوتا تھا.اجتہاد کیا ہے؟ اس کی مثال نے اس طرح دی ہے : " اکثر فقہا خیال کرتے ہیں کہ جس فقیہ نے سب
سے زیادہ آراء حفظ کی ہیں وہ سب سے زیادہ قانونی مہارت رکھتا ہے.ان کا نظریہ اس شخص جیسا ہے جو سوچتا ہے کہ
موچی وہ ہے جس کے پاس بہت سارے جوتے ہوں بجائے اس شخص کے جو جوتے خود بنا سکتا ہو.یہ بات اظہر من
الشمس ہے کہ وہ موچی جس کے پاس بہت سارے جوتے ہیں اس کے پاس ایک روز کوئی ایسا گا ہک ضرور آئے گا جس
کے پیر کا جوتا اس کے پاس نہیں ہوگا.لہذا ایسا گاہک لازماً ایسے موچی کے پاس جائے گا جو جوتے خود بنا سکتا ہو." اخلاق حسنہ کا حسین گلدستہ تھا.علم و عمل کے شجر کی سرسبز اور ثمر آور شارخ کی حیثیت رکھتا تھا.تمام اعلیٰ
اخلاق اس میں جلوہ فگن تھے.وہ ظاہری اور باطنی حسن سے مزین قلبی شرافت اور وضع داری کا دل فریب پیکر تھا.اور اس کا شفقت بھر امر بیانہ رویہ قابل ستائش تھا.اس کی فیاضی دوست دشمن سب کے لئے یکساں تھی.کہتا تھا کہ
اگر میں دوستوں کو دوں تو کچھ میں نے وہ کام کیا جو خود میری طبیعت کے مطابق تھا ، احسان تو یہ ہے کہ دشمنوں کے
ساتھ ایسا حسن سلوک کیا جائے جو طبیعت پر نا گوارا گزرتا ہو.اس کے حلم و بردباری کا ایک واقعہ یوں بیان کیا جاتا
ہے کہ ایک دفعہ کسی شخص نے مجمع عام میں اس کے خلاف دشنام طرازی کی.لیکن بجائے طیش میں آنے کے اس شخص کا ممنون ہوا کہ اس کی بدولت اس کو اپنے علم و عفو کے آزمانے کا موقعہ ملا.اس نے اس شخص کو کچھ نقد رقم بطور
تحفے کے دی لیکن اس کے ساتھ اس کو تلقین بھی کی کہ کسی اور کے ساتھ ایسا تو ہین آمیز رویہ اختیار نہ کرنا کیونکہ ہر کوئی
اس کا احسان مند نہیں ہو گا.اس کی ژرف نگاہی ، بصیرت، سربیع الہی اور شان
و قار کا ایک زمانہ قائل تھا.ایک خوش پوش ، خوش اطوار ، اور
خوش باش ، جس کے رہن سہن ، وضع قطع ، رفتار و گفتار سے نفاست جھلکتی تھی.وہ مکالمت ، مفاہمت، اور مصالحت کا
خوگر تھا.کینہ، کدورت حسد اور عداوت کے لئے اس کے دل میں کوئی جگہ نہ تھی.قریب پندرہ سال تک قاضی کے
با عزت عہدہ پر فائز رہا لیکن کسی مجرم کو سزائے موت نہ دی.اگر کوئی ایسا فوجداری مقدمہ سماعت کے لئے پیش ہوتا تو
خود کو اس مقدمے سے الگ کر لیتا، ایسے مقدمے کی سماعت اس کا کوئی نائب یا قائم مقام قاضی کرتا.کسی مدعی کے
لیوں پر اس کے ظالمانہ یا یک طرفہ طرز عمل کے خلاف حرف شکایت نہ آیا.کسی فریق کی بے جا طرف داری نہ کی.28
Page 47
ہزاروں مقدمات کی سماعت کی اور ہمیشہ ہی کوشش رہی کہ انصاف کا پلڑا بھاری رہے.درویش صفت ہونے کے ساتھ نہایت محب وطن تھا.افلاطون نے اپنی کتاب ری پبلک میں یونان
کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہاں کے لوگ دماغی نشو و نما میں دنیا کے تمام ممالک سے افضل ہیں.نے اس کتاب کی شرح میں اپنے وطن عزیز اندلس کو دماغی فضیلت میں یونان کے ہم پلہ قرار دیا.جالینوس
(Galen) نے یونان کی آب و ہوا کو سب سے زیادہ معتدل قرار دیا تھا نے کتاب الکلیات میں دعویٰ کیا
کہ سب سے زیادہ معتدل آب و ہوا پانچویں اقلیم کی ہے اور قرطبہ اسی اقلیم میں واقع ہے.وہ خلافت راشدہ کو ماڈل
جمہوری حکومت تسلیم کرتا تھا جس میں افلاطون کی ری پبلک کے تمام خواص موجود تھے.فنافی العلم تھا.حصول علم کا شوق دل میں شعلے کی طرح جلتا رہتا تھا.بچپن سے لے کر بڑھاپے تک
کتابوں کے مطالعہ میں مشغول رہا.جس طرح البیرونی نے کہا تھا کہ کتا بیں اس کی اولاد ہیں ، کچھ یہی حال ابن
رشد کا تھا.رات کے وقت بھی کتاب اس کے ہاتھ میں ہوتی تھی.(1999ء میں راقم الحروف کو قرطبہ کی سیاحت
کے دوران کے مجسمے کو دیکھنے کا موقعہ ملا تھا.مجسمے میں بھی اس کے بائیں ہاتھ میں کتاب ہے ).مؤرخ
انصاري كتاب الديباج المذهب میں رقم طراز ہے: و عنى بالعلم من صغره الى كبره ، حتى
حكى انه لم يدع النظر ولا القرأة منذ عقل الا ليلة وفاة ابيه، وليلة بنائه على ا، هله.پوری زندگی میں صرف دو راتیں ایسی آئیں جن میں :: مطالعہ سے محروم رہا، ایک وہ رات جب اس کے والد کی
وفات ہوئی اور دوسر کی وہ رات جب اس کی شادی ہوئی".مطالعہ کے ساتھ ساتھ تصنیف و تالیف کا سلسلہ بھی شب
و روز جاری رہتا.طب ، منطق ، بنیت اور فلسفہ پر 87 کے قریب کتابیں یادگار میں چھوڑیں جو میں ہزار صفحات پر
مشتمل ہیں.قاضی ابو مروان الباجی نے کی سیرت کو ان الفاظ میں بیان کیا تھا:" کی رائے نہایت
صائب ہوتی تھی.بے انتباذ کی اور قوی القلب تھا.اس کے حو صلے نہایت بلند تھے، مصائب سے کبھی خوف نہ کھاتا
تھا." (طبقات الاطباء صفحہ 76)
اتنے بڑے عالم اور مسلم الثبوت فقیہ ہونے کے باوجود اس میں علمی برتری جتانے کا رتی برابر شوق نہ تھا.دوسروں سے فراخدلانہ طور پر پیش آتا.منکسر المزاجی کا اظہار اس کے سادہ لباس سے ہوتا تھا.مال و متاع یا جائیداد
بھی کوئی نہ تھی.وہ اپنے دشمنوں سے بھی عدل کا سلوک کرتا تھا.اس کا مشہور مقولہ تھا کہ اگر میں صرف دوستوں کو کچھ
دوں تو میں نے وہ کام کیا جس کو میرا دل چاہتا تھا.سخاوت یہ ہے کہ دشمنوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے جس کو
29
Page 48
طبیعت مشکل سے گوارا کرتی ہے.(There is no virtue in being generous to a friend, but he is virtuous who
gives to an enemy.)
وہ دوست و دشمن سب کے لئے فیاض تھا.اگر اس کے کسی دوست کو کوئی بلا وجہ ہدف تنقید بناتا تو وہ یہ برداشت نہیں
کرتا تھا.کہتے ہیں کہ ایک شاعر کو اس نے اسی (80) کوڑوں کی اس لئے سزادی کیونکہ اس نے ایک عالم دین کی ہجو
لکھی تھی.به حیثیت فلسفی خدا کی ذات پر اس کا یقین گویا پتھر پر لکیر کی طرح تھا.اس کا مشہور مقولہ ہے:
He who studies anatomy increases his belief in God.وہ تمام اسلامی عبادات اور رسومات کی پابندی فرض منشیبی سمجھتا تھا.نہایت با حیاء کم مخرن ، حد درجہ پاک باز ، اور پا
بند صوم و صلوۃ تھا.پانچوں وقت کی نماز با جماعت مسجد میں ادا کرتا تھا.سرور کائنات ، ہادی برحق ﷺ کو خاتم النبین
دل و جاں سے تسلیم کرتا تھا.کہتا تھا کہ ہر شخص کو سب سے اچھے دین کا پیروکار ہونا چاہتے، دیکھو جب اسلام اسکندریہ
میں پہنچا تو یہاں کے علما نے اپنے مذہب کو ترک کر کے اسلام قبول کر لیا.ہمارے دور میں سب سے کامل مذہب
اسلام ہے.ایک فلسفی اور پیغمبر کے اطوار کا موازنہ کرتے ہوئے فرمایا:
Every Prophet is a philosopher, but not every philosopher can be a
prophet یعنی ہر نبی فلسفی (یعنی دانائی اور حکمت کا سر چشمہ ) ہوتا ہے لیکن ضروری نہیں کہ ہر فلسفی نبی بھی ہو.اس کے ایک ہم عصر ابو محمد عبد الکبیر کا بیان ہے: کی بے دینی کے متعلق جو باتیں مشہور ہیں وہ سراسر غلط
ہیں.وہ بے دینی کے گندے جراثیم سے بالکل پاک تھا.میں نے اس کو مسجد میں جماعت کیسا تھ نماز ادا کرتے
ہوئے دیکھا.ہر نماز سے پہلے تازہ وضو کرتا تھا.البتہ ایک بار اس کی زبان سے غلطی سے سخت کلمہ نکل گیا اس کے
علاوہ اس سے کبھی کوئی اور غلطی سرزد نہیں ہوئی.(یہاں طوفان والے واقعہ کی طرف اشارہ ہے ).تلاوت قرآن
کریم، نماز، روزه، نیز تمام شرعی احکامات کا پابند، نیک متقی ، اور مستجاب الدعوات تھا.قرآن اور حدیث کے حوالے
و امکنگ انسائیکلو پیڈیا کی طرح از بر تھے.زندگی کے آخری ایام میں اس کے دشمنوں نے اس کے متعلق غلط سلط باتیں مشہور کر دی تھیں ان میں ایک یہ
تھی کہ وہ بے دین تھا جیسا کہ عام طور پر فلسفی ہوا کرتے ہیں.رفتہ رفتہ یہ بات اس کے کیریکٹر کا حصہ بن گئی.خاص
30
Page 49
طور پر اس بات کو یورپ کے مسیحی حلقوں میں بہت پھیلایا گیا.اس کی وجہ یہ تھی کہ میسی حلقوں میں بہت سارے
عیسائی علما ایسے تھے جو اس کے فلسفیانہ نظریات کی وجہ سے اس کو دشمن ایمان جانتے تھے.یورپ میں جوں جوں
فلسفہ کی تعلیم عام ہوتی گئی اور نئی روشنی ( Enlightenment) کا دور شروع ہونے لگا تو لوگ دین سے بے زار
ہونے لگے.مسیحی پادریوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ ساری بے دینی کے فلسفہ کی اشاعت کی وجہ سے ہے.بعض لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ دراصل کا تعلق یہودیت سے تھا ظاہر میں مسلمان بنا ہوا تھا.بعض کہتے
کر نہیں وہ عیسائی تھا.اس کی بے دینی کے سلسلہ میں ایک یہ واقعہ بھی گھڑ لیا گیا: ایک دفعہ وہ گرجے میں گیا وہاں اس
وقت عشائے ربانی کی رسم یو فارسٹ (Eucharist) ادا ہو رہی تھی.نے نفرت سے لوگوں کو مخاطب ہو کر
کہا کہ تم لوگ کس قدر احمق ہو جو اپنے خدا کی بوٹیاں نوچ رہے ہو.اس کے بعد دعا کی کہ خدا مجھے فلسفیوں کی موت
عطا کر.نعوذ بااللہ یہ بھی کہا کہ اسلام بے وقوفوں کا دین ہے.یورپ میں ایک اور من گھڑت افسانہ رواج پا گیا کہ مریضوں کے لئے نسخے تجویز نہیں کرتا تھا اور
اسے طبابت کے پیشہ سے نفرت تھی.اس مغالطے کی وجہ یہ تھی کہ کتاب الکلیات میں نے قصد اور آپریشن
کے بعض سہل طریقے ابن زہر کے حوالے سے نقل کئے ہیں.یہ اعتراض اس لئے بھی بے بنیاد ہے کیونکہ کئی
سال تک خلیفہ ابو یوسف یعقوب منصور کے دربار میں شاہی طبیب کے منصب پر فائز رہا تھا.ایک زمانہ میں مغرب اور مشرق کے علما کے درمیان یہ دلچسپ بحث جاری تھی کہ کسی خطہ زمین کو فضیلت حاصل
ہے.اس ضمن میں وہ اپنے اپنے ممالک کے ممتاز علما کے نام اور ان کی تصنیفات بیان کر کے اپنے ملک کی فضلیت
ثابت کیا کرتے تھے.اس سلسلہ میں سب پہلے ابن الربیب قیروانی نے اندلس کے عبد الرحمن ابن حزم کے نام ایک
مراسلہ بھیجا جس میں شمالی افریقہ کی فضیلت اندلس پر ثابت کی.اس کے جواب میں ابن حزم نے اندلس کے علما کے
مناقب و فضائل پر ایک رسالہ لکھ کر ابن الربیب کو بھیجا.ابن حزم کے رسالہ کے ذیل کے طور پر ابن سعید بن حزم نے
مزید ایک رسالہ
لکھ کر اس کی تکمیل و توثیق کی.فلسفہ و اخلاقیات کے بیان میں اس نے کو خاص جگہہ دے کر
علماے اندلس میں سب سے زیادہ قدر و منزلت کا مستحق قرار دیا.ابو الولید شفندی نے اور اس کے دادا کو
اسلام کے روشن ستارے اور شریعت کے چراغ کے القابات سے نوازا.غرض کی رحلت کے سو برس بعد بھی
اندلس میں اس کی تصنیفات کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا رہا.ابن تیمیہ اپنے وقت کے شیخ الاسلام تھے انہوں نے کی کتاب کشف الادلہ کا رد لکھا جو ان کی
کتاب العقل والنقل میں شامل ہے.ممتاز تاریخ داں ابن خلدون نے اپنی شہرہ آفاق کتاب مقدمہ تاریخ میں کو الفارابی اور ابن سینا کے ہم پلہ قرار دیا ہے.31
Page 50
آزادی نسواں کی حمایت
آج کے دور میں عورتوں کے حقوق اور آزادی کا ہر طرف چر چا ہے.مغرب میں آزادی نسواں
(women's lib) پوری آب وتاب کے ساتھ جلوہ گر ہے.کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ اس تصور کے بیج کو مغرب میں
کس نے بویا تھا جو آج یہ تن آور درخت بن کر ایک پوری تحریک کو اپنے سایہ کے نیچے لئے کھڑا ہے؟ یادر ہے کہ حقوق
نسواں کا سب سے پہلا علمبر دار یورپ میں تھا.افلاطون کی کتاب الجمهوريه (جوامع سياسية
افلاطون ) کی شرح متوسط میں اس نے کہا ہے کہ " عورتیں تمام معاملات زندگی میں مردوں کے مساوی ہیں، ہاں
صرف یہ کہ دو فطری طور پر کمزور ہوتی ہیں.اسن اور جنگ دونوں حالتوں میں دونوں کی قابلیتمیں ایک جیسی ہیں.اس دعوئی کے حق میں اس نے یونانی، عرب، اور افریقی (بربر) جنگ جو عورتوں کا ذکر کیا ہے.مزید کہا ہے کہ ہمارے
معاشرے میں عورتوں کا مقام افلاطون کی جمہوریت میں دئے گئے شہری مساوات کے برابر کا نہیں ہے.عورتوں کو
بچے جنم دیتے ، دودھ پلانے اور ان کی پرورش کے لئے استعمال کیا جاتا ہے جو کہ ملک کی اقتصادیات کے لئے برا
نیز ریاست کی غربت کا اصل سبب ہے.اس کے نزدیک عورتوں میں حکمراں اور فلسفی پیدا ہو سکتے ہیں.(8)
اس نے مزید کہا کہ معاشرے کو اچھے سے اچھا بنایا جا سکتا ہے، اس نے معاشرہ اچھا بنانے کے طریقے بھی
بتلائے.ان سیاسی خیالات نے مذہبی علما اور سیکولر حکمرانوں اور کیتھولک پادریوں کو بھی مخمصے میں ڈال دیا کیونکہ یہ
سب گردہ چاہتے تھے کہ معاشرہ جوں کا توں قائم رہے نا ہر کس و ناکس اپنے حقوق کی بات نہ کر سکے.مکمل اقتباس ملاحظہ فرمائے : ہماری سوسائٹی میں عورتوں کے ہنرا جاگر کرنے کی کوئی جگہ نہیں ہے.بچوں کا
پیدا کرنا اور ان کی نگہداشت کرنا ان کا مقدر بن چکا ہے.اس غلامی کی حالت نے ان میں بڑے کام کرنے کی اہمیت
سلب کردی ہے، چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی عورت ایسی نہیں جس میں پر از حکمت خوبیاں ودیعت کی گئی ہوں.وہ
جڑی بوٹیوں کی طرح بے سود اپنی زندگیاں گزارتی ہیں.اپنے شوہروں کے لئے انہوں نے خود کو وقف کر رکھا ہے.اس سے وہ زبوں حالی جنم لیتی ہے جو ہمارے شہروں میں عام ہے کیونکہ عورتیں تعداد میں مردوں سے دو گنا سے زیادہ
ہیں لیکن ضروریات زندگی وہ اپنی محنت سے پوری نہیں کر سکتیں." (9)
اندلس کے اس دور کے معاشرہ میں عورت گویا مرد کی جائیداد تصور کی جاتی تھی.مرد ایک سے زیادہ شادیاں کر
سکتا تھا اور جب چاہے طلاق دے سکتا تھا.عورتیں اپنے گھروں میں محبوس رہتی تھیں علمی کام کرنے کی استعداد ان
میں مفقود سمجھی جاتی تھی.کوئی عورت فقیہ، قاضی، استاد، منصف، حاکم کی صورت میں کہیں ڈھونڈے بھی نہیں ملتی
تھی.قارئین انداز و فرما ئیں نے حقوق نسواں کی بات ایک ایسے معاشرے میں ایک ہزار سال قبل کہی تھی
32
Page 51
جہاں حکومت ، عدلیہ، انتظامیہ میں مرد ہی مرد تھے.خلیفہ گویا مطلق العنان حکمراں تھا.آمریت کا دور دور د تھا.اس
امر سے اس کی آزادی فکر اور جرات رندانہ کا انداز ہوتا ہے.حق گوئی اور با کی اس کا طرۂ امتیاز تھا.یقیناً وہ اپنے
زمانہ سے ایک ہزار سال آگے رہ رہا تھا.(He was far ahead of his time ).اس کو فری تھنکر " کا "
خطاب بھی دیا جا سکتا ہے.بہر حال اس کے دل میں جو ہوتا تھا وہی وہ زبان سے ادا کرنا تھا.افلاطون کی کتاب ری پبلک کی شرح میں اس نے پیغمبر اور فلسفی میں فرق بیان کرتے ہوئے مذہب
( اسلام ) کو فلسفہ پر فوقیت دی کیونکہ مذہب کا پیغام فلسفہ سے زیادہ عوام تک پہنچتا ہے.پیغمبر وہ کام کر سکتا ہے جو فلسفی
نہیں کر سکتا مثلاً عوام الناس کی تعلیم و تربیت ، آنے والے واقعات کا علم، مذہبی قوانین کا قیام اور انسانیت کی فلات و
بہتری کا قیام.الہام کے ذریعہ پیغمبر ایسے احکام و قوانین جاری کرتا ہے جن سے عوام یہ جان لیتے ہیں کہ انہیں کیسے
خوش اخلاقی سے پیش آتا ہے.اس ضمن میں پیغمبر کے لئے سیاسی سوجھ بوجھ رکھنا بہت ضروری ہے, کرشموں کو اس
سے کوئی سروکار نہیں ہے.لندن سے 1854 ء میں شائع ہونے والی ایک نادر کتاب حسن اتفاق سے کچھ روز قبل مجھے کنگسٹن کی کوئینز
یونیورسٹی کی اسٹافر لائبریری میں دستیاب ہوئی.اس میں کا ذکر ان الفاظ میں کیا گیا ہے:
The illustrious Alfaki Abu Walid Ben Raxid likewise held that office
(king's physician) about the person of King Abu Jakob, having been
summoned to the court of Morocco by the Ameer Almuminin for that
purpose in the year 578; but the king almost immediately appointed him
Cadi of Cordova...Abu Walid was not only a distinguished physician, but
was well versed in many other branches of knowledge.Aben Alged
assures us that he was an excellent poet.and he is said to have repeated all
the translations of Bochari.He died at Morocco on the 21st day of moon
Dylhajia in the year 595.(10)
( ترجمہ ) عالم و فاضل فقیہ ابو ولید بن رشد بادشاہ ابو یعقوب کا شاہی طبیب تھا.578 ہجری میں
امیر المومنین کے حکم پر اس کو دربار میں مراقش بالا یا گیا لیکن بادشاہ نے جلد ہی اس کو قرطبہ کا قاضی مقرر کر دیا.ابو ولید
نہ صرف ایک ممتاز طبیب بلکہ دوسرے علوم میں بھی مہارت تامہ رکھتا تھا.ابن وفید ہمیں یقین دلاتا ہے کہ وہ بہت عمدہ
33
Page 52
شاعر تھا نیز اس کو بخاری شریف کے تمام تراجم یاد تھے.اس کی وفات مراتش میں ذی الحجہ کے چاند کے اکیسویں روز
595 ہجری میں ہوئی".کو عربی کے علاوہ کسی اور زبان سے شناسائی حاصل نہ تھی.اس لئے ارسطو کی کتابوں کی جو شر میں
انہوں نے لکھیں ان
کا انحصار سر اسران عربی تراجم پر تھا جو بغداد میں حسین ابن الحق ، اس کے بیٹے الحق ، بھانجے جیش ابن
الاعصم ، اور عیسی ابن بیٹی وغیرہ نے آٹھویں اور نویں صدی میں کئے تھے.نے کثیر تعداد میں کتابیں تصنیف
کیں لیکن کسی کتاب میں بھی اپنی زندگی کے حالات درج نہیں گئے.کتاب الکلیات کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے
کہ غذا کے معاملہ میں اس کو جو چیزیں سب سے زیادہ مرغوب تھیں ان میں جو کا پانی ( آش جو ).چاول کی کھیر ، اور بینگن
کی ایسی بھیجیا جو تیسے میں زیتون کے تیل میں بھنی ہوئی ہو.پھلوں میں انگور اور انجیر بہت پسند تھے.افسوس کہ اس عظیم المرتبت مفکر اور حکیم کو مغرب نے سر آنکھوں پر بٹھایا لیکن مشرق میں وہ صد ہا سال تک
گمنام رہا.34
Page 53
باب دوم
ایک عظیم مصنف بحیثیت مصنف اور فقیہ
عربی ادب میں کا نام آتے ہی عجب فرحت و انبساط کا احساس ہوتا ہے.ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بہت عمد :
خوشبو سونگھ لی گئی ہے.اس کی زندگی کے سرسری جائزہ سے اس کی زندگی کے ایسے حیرت کن گوشے سامنے آتے ہیں
جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا مطالعہ کس قدر وسیع اور اس کا ذہن کتنا تنقیدی اور تحقیقی تھا.اس کا روشن دماغ اور عقابی
نظر ہمیشہ بلند نظر مضامین پر قلم اٹھانے کے لئے سرگرداں
رہتی تھی.سچ تو یہ ہے کہ اس
کا زور علم اور تنجح ہی تھا جس نے
تاریخ عالم میں اس کو جائز مقام عطا کیا.بلا شبہ فضل و کمال کا انسان تھا، اس کے باوجود مشرق میں گمنام رہا.میرے خیال میں اس کی وجہ یھی کہ اس دور کے معاشرہ میں فلسفیوں کو نظر تحسین سے نہیں دیکھا جاتا تھا.نیز مشرق
میں فلسفہ کے رد میں امام غزالی کی کتاب تهافت الفلاسفہ کا دانشوروں پر بہت گہرا اثر تھا جس کے سبب
فلسفہ، منطق کے علوم کی تحصیل کو لوگ اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے.رفتہ رفتہ لوگوں نے سائنسی علوم کی تعلیم حاصل کرتا
بند کر دی اور قوم تعرمذلت میں گرگئی.اس موضوع پر مزید بحث اس کتاب کے چوتھے باب میں کی گئی ہے.ارسطو کی کتابوں پر کی تفاسیر سند کا درجہ رکھتی ہیں.انہوں نے یورپ میں شہرت دوام حاصل کی.اس
کودی کمنٹیٹر (The Commentator) یعنی شارح اعظم کے تعریفی نام سے یاد کیا جاتا تھا.فرانس کے فاضل
تاریخ داں اور فلسفی پر و فیسر ارنسٹ رینان (1892-1823 Ernst Renan) نے اس کے حالات زندگی اور
فلسفہ پر ایک کتاب ایوروس ایٹ لا ایور دازم (1852 Averroes et l'Averroisme, Paris )لکھی ہے.اس کتاب پر اس کو ڈا کٹریٹ کی ڈگری لی تھی.اس کا انگریزی ترجمہ حیدرآباد میں کیا گیا جو 1913ء میں شائع ہوا.اس کے بعد معشوق حسین خاں نے اس کا اردو ترجمہ کیا جو دارالترجمہ، جامعہ عثمانیہ سے 1929 ء میں شائع ہوا.لائبریری آف کانگریس میں پر اردو میں ایک اور کتاب موجود ہے جو عبدالواحد خال(1956-1917ء)
35
Page 54
؟.نے لکھی ہے.یہ 320 صفحات پر مشتمل ہے مسلمانوں میں سات سو سال تک گمنام رہا.اس کے علمی شاہکاروں سے دلچسپی بیسویں صدی میں پیدا
ہوئی جب ایک عیسائی عرب صحافی فرح انطون نے جوٹر پولی (لبنان) کا رہنے والا تھا، اپنے رسالہ مجلات
الجامعه (اسکندریه مصر ) میں و فلسفته کے عنوان سے کئی مضامین لکھے.ان مضامین کی اشاعت
کے بعد مصر میں خوب گرما گرم بحث چھڑی جس میں علامہ حمد عبیدہ نے بھی حصہ لیا.چنانچہ فصل المقال جو میونخ
سے 1859 ء میں ایم.ہے.میولر ( Muller) نے شائع کی تھی وہ قاہرہ سے 1894ء میں شائع ہوئی.پھر
1960ء میں ماجد فخری نے فیلسوف قرطبه " کے عنوان سے ایک کتاب لکھی، جومحمد موسیٰ نے
1959ء میں بین الدین والفلسفه قاہرہ سے شائع کی.محمد لطفی جمعہ نے مسلمان فلاسفہ کے حالات پر اپنی
كتاب فلاسفة الاسلام فی المشرق والمغرب میں کا مبسوط تذکرہ کیا.دارالترجمہ جامعہ عثمانیہ
نے اس کا اردو ترجمہ شائع کیا ہے.اردو زبان میں سب سے پہلا مضمون مولوی سید حسین بلگرامی نے کی سواغ پر لکھا جو ان کے مجموعہ
مضامین میں شامل ہے.اس کے بعد مولاناشبلی نے الندوہ میں کے حالات پر طویل مضمون تحریر کیا.پھر
مولوی محمد یونس فرنگی محل نے اردو میں 389 صفحات پر مشتمل کتاب " " لکھی جو دارالمصنفین
سے 1952ء میں شائع ہوئی.قاہرہ سے دار المعارف نے 1953 ء میں ، الطبیب کے نام سے اس کی زندگی
پر ایک کتاب شائع کی.فرانسیسی زبان میں اس کی زندگی پر ایک کتاب 1948 ء میں لیو آن گا تھیر نے پیرس سے
شائع کی (Ibn Rochd by Leon Gauthier, Paris).پچاس سال بعد اب اس کی زندگی پر علی گڑھ
مسلم یونیورسٹی سے اردو میں یہ کتاب شائع ہو رہی ہے.رینان کے مطابق ارسطو نے کائنات کی تشریح اور نے اس کی توضیح کی.مائیکل اسکاٹ اور راجر بیکن
نے اسے ارسطوئے ثانی کیا ہے.اس کا سب سے بڑا علمی کارنامہ ارسطو کی 38 نادر الوجود کتابوں کی شرح اور
تلخیص ہے.وہ ارسطو کو صاحب المنطق کے لقب سے یاد کرتا تھا.یہودیوں نے یورپ میں کی
کتابوں کے بہت سے تراجم کئے.اٹلی کی پیڈ وا (Padua) یو نیورسٹی کے مطبع خانے نے اس کی سب سے زیادہ
کتابیں شائع کیں.چنانچہ ایک سو سال یعنی 1580-1480 ء کے عرصہ میں اس کی کتابوں کے ایک سو تراجم کئے
گئے.اس کی کتابوں کے عربی اور لاطینی میں قلمی نسخے میڈرڈ سے چالیس کلو میٹر دور اسکور پال لائبریری میں موجود
ہیں.راقم الحروف نے اس عالی شان محل نما کتب خانے کو 1999 ء میں دیکھا تھا.نیز اشبیلیہ اور قرطبہ کی سیاحت
36
Page 55
کے دوران قرطبہ کی تاریخی مسجد اور دوسرے مقامات (مدینۃ الزہراء ) کے علاوہ کا مجسمہ بھی دیکھا تھا جس
کے بائیں ہاتھ میں ایک کتاب ہے.شہر کے اندر ایک محلہ میں موسیٰ ابن میمون کا مجسمہ بھی دیکھا جس کے پاؤں کو
وہاں موجود یہودی سیاح چوم رہے تھے.اسکور یال لائبریری کے ایک مخطوطہ میں (عربی نسخہ نمبر 879) میں کی طلب، فلسفہ، فقہ، کلام کی 80
کتابوں کی فہرست دی گئی ہے.ان کتابوں کے کل صفحات میں ہزار بنتے ہیں.ارنسٹ رینان نے کتاب ایوروس
اور ایوروس ازم (1852 Averroes et l'Averroisme, Paris ) میں اس کی کل کتابوں کی تعداد 67 بیان
کی ہے اس میں 28 فلسفہ، 5 علم کلام، 4، علم بیت 2 صرف ونحو 8 فقہ اور 20 طب کی کتابیں ہیں.اسلامی لٹریچر میں ابن سینا کو اشیخ الرئیس الکندی کو الفيلسوف العرب، الغزائی کو الامام اور کو قاضی
کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے.سلطان المنصور کے شاہی فرمان پر کی فلسفہ کی کتنی کتابوں کو قرطبہ میں نذر آتش
کیا گیا ، اسکا اندازہ لگانا محال ہے.مؤرخ ابن ابی اصیحہ نے طبقات الاطباء جلد دوم میں اس کی پچاس کتابوں
کے نام گنوائے ہیں.ان کتابوں کا ایک کثیر حصہ ارسطو اور جالینوس کی کتابوں کی تفاسیر پر مشتمل ہے.اس فہرست
میں فلسفہ، طب اور فقہ پر طبع زاد کتا بیں بھی شامل ہیں.تصانیف لاطینی میں سولہویں صدی میں ارسطو کی کتابوں کا مجموعہ ایڈ یشو پرنسپ ( Editio Princeps) کی
شرحوں کے ساتھ دینیس سے پچاس مرتبہ شائع ہوا تھا.سلی اور اٹلی کے شہنشاہ فریڈرک دوم نے جو اسلامی تہذیب کا
اس قدر دلدادہ تھا کہ پادری اس پر مسلمان ہونے کا الزام عائد کرتے تھے ، اس نے کی کتابوں کے ترجمے
اپنی سرپرستی میں مائیکل سکاٹ سے کرائے تھے.اٹلی کے عالم اینڈریا الپا گو (1520 Andrea Alpago) نے
بھی کی کتابوں کے چند ترجمے کئے.غرضیکہ کی شرحوں کے تراجم نے عیسائی اور یہودی عالموں پر
گہرا اثر چھوڑا.ٹامس آرنلڈ نے اپنی کتاب لیگیسی آف اسلام (Legacy of Islam) میں کہا ہے:
"Ibn Rushd belongs to Euorpe and European thought rather than to the
East, In Italy his influence lived on into the 16th century.Averroism
continued to be living factor in European thought until the birth of
modern experimental science."(11)
37
Page 56
انین کے عالم مینوئیل الانسو ( Manuel Alonso) نے 1947ء میں میڈرڈ سے ایک کتاب
نیو لوجیاؤ کی ایورویس (Toologia de Averroes) شائع کی جس میں کے سارے لاطینی تراجم کا ذکر
کیا.اس کے بعد عبرانی زبان میں اس کی تمام کتابوں کی اشاعت کی گئی.عربی زبان میں کل کتابوں (58) کا تاریخ
وار ذکر جمال الدین العلوی نے اپنی کتاب المتن الرشدی ( دار البیضا 1986ء) میں کیا ہے.اس ضمن میں
ایک تازہ کتاب بانس دے بر (Hans Daber) کی بلیو گرانی آف اسلامک فلاسفی ( Bibliography of
1999 Islamic Philosophy, Brill ) ہالینڈ سے شائع ہوئی ہے.ذیل میں کی تمام تصنیفات کی فہرست تاریخ وار پیش کی جارہی ہے اس میں وہ تمام کتابیں بھی شامل
ہیں جو اس نے ارسطو کی کتابوں کی تشخیص ، جوامع یا شروح کے بطور لکھی ہیں.اس فہرست کے مطابق کل کتابوں کی
تعداد 101 بنتی ہے جو انٹرنیٹ سے حاصل کی گئی ہے:
http://nig.op.org/kenny/rushchron.html
المختصر في المنطق مختصر، الا سا جوجی - مختصر المعقولات مختصر
العبارة - مختصر القياس مختصر التحليل مختصر البرهان - مختصر الفطة.مختصر الجدل - مختصر الخطابة مختصر الشعر ( مختصر سے مراد شرح صغیر ہے )
مختصر المستصفى الضرورى فى اصول فقه امام الغزالی کی فقه پرکتاب
المتصفى كا خلاصه
الجوامع الطبيعة - جوامع ا لسماع الطبيعي.جوامع السماء و العالم - جوامع
الكون والفساد ( کیمسٹری پر).جوامع الاثار العلوية (میٹرلوجی)
المختصر في )
النفس.جوامع ما بعد الطبيعة (میٹا فزکس)
+1157
+1158
+1159
+1160
+1161
1162 كتاب الكليات في الطلب
بداية المجتهد و نهاية المقتصد
تلخیص کتاب ایسا غوجى - تلخيص المعقولات تلخيص العبارة )
تلخیص سے
مراد شرح متوسط ہے)
تلخيص القياس
تلخيص الجدل.38
+1164
* 1165
+1166
+1168
Page 57
تلخيص البرهان - تلخیص کتاب الحيوانات ) زولوجی) - تلخيص من اعضاء
الحيوان
مختصر المجسطى (Almagest) - جوامع الحس والمحسوس بمقام اشبیلیہ).تلخيص السماع الطبيعي
تلخيص السماء و العالم De Caelo
تلخيص الكون والفساد مقاله فى المحمولات المفردة والمركبة - مقاله في
جهات النتائج في المقانيس - مقاله في المقدمه الوجودية او المـ
المطلقة.تلخيص الاثار العلوية (اس کتاب میں قرطبہ میں 1170ء میں آنے والے زلزلہ کا ذکر کیا ہے)
تلخيص كتاب النفس - تلخيص ما بعد الطبيعة - تلخيص السفسطة.تلخيص كتاب الخطابة (Rhetoric)
تلخيص الشعر (Poetics)
تلخيص كتاب الاخلاق - تلخيص سياسة فلاطون كتاب الجمهورية
وہ کتابیں جن پر نظر ثانی کر کے نے مقالے لکھے وہ بھی تعداد میں کافی ہیں
مقاله في نقد مذهب تا مسطیوس - مقاله فى القياس الشرطي مقاله في نقد
مذهب ابن سینا - تعليق على قول لابى نصر فی کتاب البرهان
مقاله في الكلمه والاسم المشتق و نقد مذهب ابی نصر - مقاله في الحد وتقد
مذهبي الاسكندر و ابی نصر
مقاله
-
مقاله في الكليات - مقاله في حد الشخص مقاله فى ثلاثه نوع المحدود مقاله
في الحد الاوسط - مقاله فى الشرائط مقدمات البرهان مقدمات في الشروط -
علم الى علم آخر مقاله فى براهين الوجود مقاله في كيف الحد
من
مقاله في الحدود - مقاله في زمان النوبة - مقاله في حفظ الصحة.مقاله في
الصحة - مقاله فى الترياق - مقاله فى البذور والزروع - مسائل في الطبيعة - مقاله
في جوهر الفلك.مقاله في الشعر.مقالة في العلم الالهي الضميمة) - فصل المقال
الكشف عن
منا هيج الأدلة في عقائد الملة
شرح ارجوزة ابن سينا فى الطب - مقاله فى اصناف المزاج ونقد مذهب
39
+1169
+1170
+1171
+1172
+1173
+1174
+1175
1176
+1177
+1174
+1178
F1178
+1179
+1180
Page 58
جالینوس مقالة في حيلة البر
تهافت التهافت مقاله في ان ما يعتقده المشاؤون
مقاله فى مفارقة المبداء الاول - مقاله في الخطابه Rhetorics - مقالة في
السماء و العالم (De Caelo)
مقاله في جهت نتائج القائيس ۱۱۸۳ : مقاله فی لزوم جهات الى النتائج
لجهات المقدمات مقاله في محمولات البراهين
شرح البرهان
شرح السماع الطبيعي
شرح السماء والعالم (De Caelo)
شرح كتاب النفس (De Anima
تلخيص كتاب الاسطقسات، تلخيص كتاب المزاج، تلخيص كتاب القوى
الطبيعية، اختصار العلل والااعراض
تلخيص كتاب الحميات، تلخيص كتاب الادوية المفردة ، مقاله في زمان
النوبة تلخيص كتاب الادوية المفردة
+1181
+1182
1183
+1184
+1188
+1190
+1192
1193
+1194
تلخيص رسالة الاتصال لابن باجة ، مقاله في اتصال العقل المفارق بالانسان
رسالة الاتصال - شرح مقالة لا سكندر الافروديسي في العقل ، شرح ما بعد
الطبيعة (Metaphysics)
1195ء (فروری) مقالة فى معنى المقول على الكل وغير ذالك
#1196
مقالة على المقالة السابعة والثامنة من الماع الطبيعي لارسطو
(نومبر) (یہ صرف ایک مقالہ ہے جسے اس نے نظر بندی کے دوران لکھا تھا ) کی تصنیف و تالیف کا زمانہ 1157 ء سے 1196 ء تک پھیلا ہوا ہے یعنی 39 سال کا عرصہ.اس کے
اشہب قلم سے جو کتا بیں منظر عام پر آئیں ان پر طائرانہ نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس
کی تحریروں کے تین دور
تھے.پہلے دور میں جب ملک میں سیاسی خلفشار تھا تو اس نے مختصرات (شرح صغیر ) لکھیں.دوسرے دور میں جب
ملک میں سیاسی اطمینان تھا تو اس نے جوامع ( شرح متوسط) لکھیں پھر جب ملک میں مزید سیاسی استحکام قائم ہوا تو
اس نے تفاسیر اور شروح ( شرح بسیط ) لکھیں نیز طب میں تلخیص مرتب کیں.وہ اپنی تحریروں سے کبھی مطمئن نہیں
ہوتا تھا اس لئے پرانی تلاجی ، جوامع اور شروح پر نظر ثانی کرتا رہتا تھا.اور اس کی روشنی میں مقالہ جات لکھتا
40
Page 59
تھا.جنہیں آجکل ہم پوسٹ پہلی کیشن نوٹس کہتے ہیں.مجموعہ یا جوامع کی مثال کے طور پر ارسطو کی پانچ کتابیں ہیں: Physics, De Caelo et Mundo
De Generation el Corruption, Meteorologica اور Metaphysica.ان میں اس نے
ارسطو کے خیالات کو ترتیب وار پیش نہیں کیا ہے.شرح متوسط کی مثال ارسطو کی کتاب کیٹیگوریز (Categories)
بھی ہے جس میں ہر پیراگراف کے آغاز میں قبال ارسطو لکھ کر پھر اس کا اصل عربی متن پیش کیا ہے.کیٹیو ریز کا
انگریزی ترجمہ بوجھیں (Bouyges) نے کیا ہے جو 1932 ء میں شائع ہوا ہے.کی کتابوں کا تنقیدی جائزہ
بارہویں صدی کے جو ادیب اور عالم عربی زبان وادب میں مینارہ نور کی حیثیت رکھتے ہیں ان میں کا
نام سر فہرست ہے.نے بالغ نظری اور سادو و پر کار اسلوب بیان کے ذریعہ عربی تنقید میں سنگ میل قائم کیا
ہے.اس میدان میں اس کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے.این رشد نے اپنی گراں مایه نگارشات سے نہ صرف عروس البلاد قرطبہ کا نام روشن کیا بلکہ عربی زبان کے ایک
عالمی بصیرت نگار کی حیثیت سے بھی شہرت دوام حاصل کی.وہ جب اکتیس سال
کی عمر کو پہنچا تو علوم حکمیہ و عقلیہ میں
اپنی استعداد مکمل کرنے کے بعد، اس نے اپنا ذرخیز ذہن تصنیف و تالیف کی طرف متوجہ کیا.قاضی القضاۃ کے عہدہ
کے فرائض سر انجام دینے کے لئے اس کو شہروں اور صوبوں کے سرکاری دورے کرنے پڑتے تھے مگر اس کے ساتھ
ساتھ کتابوں کے لکھنے لکھی ہوئی کتابوں پر نظر ثانی کرنے کا کام بھی شب و روز جاری رہتا تھا.اکثر کتا ہیں اس نے
بیحد مشغولیت کی حالت میں قلم بند کیں.وہ جب اشبیلیہ میں قاضی تھا تو اس کی ذاتی لائبریری کی جملہ کتابیں قرطبہ
میں تھیں اس کا ذکر اس نے کتاب الحیوان کے چوتھے حصہ کی شرح میں کیا ہے.پھر ارسطو کی ایک اور کتاب کی
شرح میں شکوہ کیا ہے کہ سرکاری کاموں کی مسجد سے فرصت نہیں ملتی.زیادہ وقت دفتری کاموں میں صرف ہو جاتا ہے
اور قلبی سکون میسر نہیں ہوتا جو تصنیف و تالیف کے لئے ضروری ہوتا ہے.کتاب مختصر المجسطی کے مقالہ
اولی میں لکھا کہ مجھے مجبور آصرف اہم مسائل کی حد تک رہنا پڑتا ہے کیونکہ میری مثال اس شخص کی سی ہے جس کے گھر
کے چاروں طرف آگ لگی ہوئی ہو اور صرف اتنا موقعہ ہو کہ جو اشیاء بے حد ضروری ہیں انہیں بچانے کے ساتھ اپنی
جان بھی بچالے.یہ باتیں اس کے ذوق تصنیف لگن ، اور دینی ارتکاز پر دلالت کرتی ہیں.نے جن گونا گوں موضوعات پر قلم اٹھایاوہ اس کی فطری استعداد کی نماز ہیں.دینی علوم کا علم اس کو
41
Page 60
ورثہ میں ملا تھا جبکہ یونانی علوم اور علوم عقلیہ میں ذاتی مطالعہ سے کمال حاصل کیا تھا.آج کل ایسے شخص کو سیلف ناٹ
مین (self-taught man) کہا جاتا ہے.جارج سارٹن کی رائے میں وہ پیدائشی عبقری نہ تھا بلکہ جو کچھ حاصل کیا
وہ نذیر اور تفکر سے حاصل کیا:
Ibn Rushd was not a creative genius, but a purely reflecting one.(12) کی تصنیفات کے موضوعات درج ذیل ہیں.صرف و نحو، اصول فقہ، علم کلام، منطق، فلسفه علم
الاخلاق علم النفس، طبعیات، سیاسیات، علم الحیوان علم الابدان، علم فلکیات ، طلب
بظاہر کی تصنیفات میں کوئی خاص جدت نہیں پائی جاتی مثلا طب میں اس کی معلومات جالینوس کی
کتابوں تک محدود تھیں.اس کا فلسفہ اگر چہ ارسطو سے ماخوذ ہے لیکن اس نے چابکدستی سے اس کو اندلس کے ماحول
اور اسلامی روایات کے مطابق ڈھالا ہے.اس کی فقہ وہی تھی جو اس کے معاصرین کی تھی.اس کی الکلیات فی
الطب' کو بوعلی سینا کے القانون فی الطب جیسی پایه دار شہرت حاصل نہ ہوسکی.لیکن کا خاص امتیاز
اس کی قوت تنقید ہے.تحصیل علم کے لئے قوت تنقید بنیادی چیز ہے جو اس زمانے کے مسلمانوں میں کم پائی جاتی تھی،
زیادہ تر لوگ تقلید کرتے تھے.نے اجتہاد سے کام لیا اور نئے نئے خیالات و مشاہدات سے اندلس کے افق
علمی کومنور کیا.وہ اپنے مافی الضمیر کا اظہار اس وضع سے
کرتا تھا کہ اس سے قول فیصل کی صدا آتی تھی.یہ اس لئے کہ
اس کی عبارت کی ساخت میں استدلال کی اینٹیں لگی ہوتی تھیں.تحریرہ میں پختگی اور صلابت بڑی کاوشوں کے بعد اس
کو حاصل ہوئی تھی.عربی زبان کے سوا اس وقت کی دیگر علمی و سائنسی زبانوں سریانی ، فارسی، لاطینی، یونانی بلکہ طرفہ یہ کہ
اپنی وطنی زبان اسپینش سے بھی نا واقف تھا.اس نے ارسطو کی تصنیفات کی شرحیں اور خلاصہ جات ان عربی تراجم کی
روشنی میں مرتب کئے ، جو تین سو سال قبل حسین ابن الحق، الحق ابن حسنین، ابو بشرمتی پٹی بن عدی ، ثابت ابن قرة نے
بغداد میں کئے تھے.نے کئی یونانی الفاظ کے متبادل الفاظ عربی میں خود وضع کئے جیسے افلاطون کی کتاب کی
شرح لکھتے ہوئے لیجسلیٹر ( legislator ) کا ترجمہ اس نے صاحب الشريعة ( ما شرآف لا) کیا.مذہبی
قانون کے لئے یونانی لفظ نوموس (Nomos) کا ترجمہ اس نے شریعت کیا.اسی طرح حج کے لئے یونانی لفظ کا
ترجمہ اس نے (بجائے قاضی کے ) حکیم کیا کیونکہ اس لفظ کی اصل حکم ( دانائی) ہے.نے جہاں ترجمہ میں نقص پایا ، وہاں اس نے ترجمہ خود کیا اور ارسطو کے مفہوم کو اچھی طرح سمجھ کر اسے
بہتر طریق سے ادا کیا.مثلاً ارسطو اپنی کتاب الجدل (Rhetoric) کی ابتداء میں مدعی ، حج ، اور قانون ساز کی بات
42
Page 61
کرتا ہے جو کہ یونانی عدلیہ کی طرف صریح اشارہ ہے.نے اس آئیڈیا کو اندلس کے اسلامی ماحول کے مطابق
ادا کیا تا کہ لوگ اس کا مفہوم آسانی سے سمجھ سکیں.شہادت کے بارے میں ارسطو کہتا ہے کہ مدعی خود اپنی شہادت پیش کر
سکتا ہے لیکن اس کے لئے مدعی کی شخصیت کو محوظ خاطر رکھنا ضروری ہے.نے اس کی شرح یوں کی کہ اول
شہادت تو یہ ہے کہ مدعی جب اپنے حق میں بیان دیتا ہے تو وہ اپنی قابلیت خود ثابت کرتا ہے جس کے ذریعہ اس کو قابل
اعتماد سمجھا جاتا ہے.اس دلیل کے حق میں نے قرآن پاک کی آیت 68: 7 و انا لکم ناصح امین (اور
میں تمہارے لئے قابل اعتماد نصیحت کرنے والا ہوں) پر انحصار کیا جو حضرت ہود نے بطور شہادت کے کہا تھا.ایک
مسلمان بیج کی حیثیت سے اس طرح اس نے یونانی فلسفہ اور اسلامی قانون میں تطبیق اور ہم آہنگی پیدا کی.جیسا کہ ذکر کیا گیا کہ یونانی تہذیب سے اس کی واقعیت بہت محدود تھی اور یونانی زبان سے یاد اللہ راجبی ہی
تھی اس لئے اس نے بعض مرتبہ یونانی حکما کے ناموں کے سلسلہ میں غلطی کھائی اور دو مختلف افراد کو ایک سمجھا جیسے وہ
فیثا غورث (Pythagoras) اور ڈیمو کریٹس (Democrates) میں فرق نہ کر سکا.وہ یونانی ادب سے بھی
نا واقف تھا اس لئے یونانی شاعری کی متعدد اقسام ٹریجڈی کامیڈی ، ڈرامہ اور ایک (epic) میں فرق نہیں کر سکا.اس نے سمجھا کہ ٹریجڈی ، مدحیہ شاعری اور کامیڈی ہجو آمیز شاعری کا نام ہے.اس نے اہل عرب کے کلام بلکہ
قرآن مجید سے بھی ان کی مثالیں تلاش کرنے کی بے سود کوشش کی.یونانی فلاسفہ اور فلسفہ کے مختلف گروہوں کے
ناموں کو بھی اس نے خلط ملط کر دیا.مگر یادر ہے کہ ایسی فاش غلطیاں دوسرے مسلمان شارحین ارسطوت بھی سرزد
ہوئی تھیں جیسے ابن سینا کتاب الشفاء میں رقم طراز ہے کہ کامیڈی وہ نظم ہے جس میں کسی شخص کے افعال قبیحہ
کھول کر بیان کئے جاتے ہیں.یونانی فلسفیوں میں اسکندر افرود روی (Alexander of Aphrodisia) نے ارسطو کے فلسفہ پر شروح
لکھی تھیں، نے اس کے خیالات کو ہدف تنقید بنایا.ابن باجہ کو دو اندلس میں فلسفہ کا باوا آدم کہتا تھا.ابن سینا
کی اس نے مخالفت کی جس کا سبب اس کی مذہب کی تردید ہے.امام غزائی سے اس کی مخالفت کی وجہ یہ تھی کہ انہوں
نے فلسفہ کو برا اور فلسفیوں کو زندیق قرار دیا تھا.ارسطو کے ساتھ اس
کی شیفتگی انتہائی درجہ کی تھی وہ اس کو صاحب
المنطق کے لقب سے یاد کرتا تھا.ارسطو کی تعریف و توصیف کے باب میں اس نے لکھا ہے کہ جس شخص کو ایسی نعمتیں
ودیعت کی گئی ہوں اسے انسان کے بجائے دیوتا کہا جائے تو بجا ہے.ایک اور جگہ لکھا کہ ارسطو کے مسائل بالکل حق
ہیں، چونکہ اس کا دماغ ذکاوت انسانی کی انتہا ظاہر کرتا ہے اس لئے یہ کہنا بجا ہوگا کہ خدا نے اتنی اعلی وارفع تعلیم
دینے کے لئے اس شخص کو پیدا کیا جس قدر حاصل کرنا ہمارے امکان میں داخل تھا.43
Page 62
مغربی مصنف را جر آرنلڈس نے کی دیو قامت علمی شخصیت کو درج ذیل چند گنے چنے الفاظ میں بیان کر
کے گویا سمندر کو کوزے میں بند کر دیا ہے:
"It is unquestionable that his openness of mind, his rigorous method, his
analyses, not to mention his innovations, several of which can put us onto
the path of new research, are examples which can still be profitably
utilized today in the teaching of Philosophy." ( 13)
( اس بارے میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کی وسیع النظری ، اس کا سخت ( سائنسی ) طریق کار، تجزیہ ، اور وہ
جد میں جو اس نے کیں جن میں کئی ایک اب بھی نئی ریسرچ کی طرف ہماری رہنمائی کر سکتی ہیں، یہ ایسی مثالیں ہیں جن
کو فلسفہ کی تعلیم میں اب بھی سود مند طریقہ سے استعمال میں لایا جا سکتا ہے.)
اس باب کا خلاصہ چھ لفظوں میں یہ ہے: علم کا سمندر تھا.ایک بے مثل فقیہ ایک بے مثل فقیہ تھا اور فقہی معاملات میں ید طولیٰ رکھتا تھا.یہ علم اور ذوق اسے دادا اور باپ سے
وراثت میں ملا تھا.قانونی مہارت اس کے رگ وریشہ میں رچی ہوئی تھی.فقہ اور حدیث میں اس کی مہارت
کا یہ عالم
تھا کہ بقول ابن الآبار ان علوم میں اندلس میں اس کا کوئی ثانی نہ تھا.اس کی زبر دست علمیت اور شہرت کے پیش نظر
1169ء میں اسے اشبیلیہ کا قاضی مقرر کیا گیا.دو سال بعد قرطبہ کے قاضی محمد بن مغیث کی وفات پر 1171ء میں
قرطبہ کے قاضی کے عہدہ پر فائز ہوا.قاضی ایسا سرکاری افسر ہوتا تھا جس کے ہاتھ میں عدلیہ کے تمام اختیارات
ہوتے تھے.چونکہ خلیفہ ملک کا حکمراں ہوتا تھا اس لئے قاضی کا تقرر خلیفہ خود کرتا تھا.اندلس میں قاضی کی معاونت
کے لئے مجلس شوری ہوتی تھی جس سے وہ مشورہ کرتا تھا.مشاورت کا اصول قرآن پاک کی آیت کریمہ 42:38 و
شاورهم في الامر اپنی تھا.اس لئے قاضی کے سامنے جب کوئی مشکل مقدمہ سماعت کے لئے آتا، تو دوان
اراکین سے مشورہ کرتا تھا.قاضی کے لئے دیوانی اور فوجداری معاملات میں صلاحیت رکھنا ضروری ہوتا تھا جن کے
فیصلے شریعت کے قوانین کے مطابق کئے جاتے تھے.مزید برآں قاضی کے لئے مختلف اسلامی مذاہب کے عقائد
اور اصولوں کا علم رکھنا بھی ضروری ہوتا تھا تا کہ وہ مقدمہ کا فیصلہ فریقین کے مسلک کے مطابق کر سکے.اندلس میں
قاضی الجماع ( کمیونٹی حج ) کو قاضی القضاۃ کہا جاتا تھا.جس کا رواج بغداد کی عباسی خلافت کی طرز پر تھا.قاضی
44
Page 63
القضاة تمام عدالتی انتظامیہ کا ذمہ دار ہوتا اور وہی صوبوں میں قاضی مقرر کرتا تھا.ایک مقدمے کا فیصلہ
مراقش کے تیرہویں صدی کے معروف مؤرخ عبد الواحد مراقشی نے کے ایک مقدمے کا ذکر کیا ہے:
قرطبہ میں ایک نامور ، دانشور استاد تھا جس کو لوگ وزاغی (چھپکلی ) کہتے تھے.اس کے ایک شاگرد کو لوگ غرنوق
(ساری) کہہ کر بلاتے تھے.غرنوق ایسے نوجوان کو بھی کہتے ہیں جس کا چہرہ نہایت خوبصورت ہو.اس استاد کے
دیگر شاگردوں کو شک ہوا کہ شاید ہمارا استاد اس پری چہرہ لڑکے کے عشق میں مبتلا ہے.جب کہ فی الحقیقت ایسی کوئی
بات نہیں تھی کیونکہ خدا نے استاد کو اس گناہ سے محفوظ رکھا تھا.ایک طالب علم نے استاد کی ہجو ملیح لکھی جو کچھ اس طرح
تھی:
اے دیوار پر چپکی چھوٹی سی چھپکلی
ایک دلفریب پرندہ تمہارا دل بہلاتا ہے
کیا ایسی چیز ممکن ہے؟
تم تو دیواروں پر چپکی رہتی ہوجبکہ و د پرواز کرتا ہے.استاد کو جب اس جو کا علم ہوا تو اس نے کی عدالت میں بہتک عزت کا مقدمہ دائر کردیا.نے
سماعت کے بعد شاعر کو جسمانی سزاسنائی.مورخ نے سزا کی تفصیل بیان نہیں کی لیکن یہ سزا قرآن میں بیان کردہ حد
کے سوا کوئی اور نہیں ہو سکتی.یعنی شاعر قذف کا مورد ہوا جس میں اسی (80) کوڑے لگائے جانے کا حکم ہے.قذف
کا جرم اس وقت سرزد ہوتا ہے جب کوئی شخص کسی نیک بے گناہ انسان پر چار گوادلائے بغیر کسی گندے فعل کے
ارتکاب کا الزام عائد کرتا ہے.قرآن پاک (24:4) میں نیک عورتوں (محسنات ) کے خلاف گندی افواہ پھیلانے
کا ذکر کیا گیا ہے:
والذين يرمون المحصنت ثم لم ير تابو ١ باربعة شهدا فاجلدو هم ثمنين جلدة ولا
تقبلوا لهم شهادة ابداً" (النور)
اور جو لوگ تہمت لگائیں پاک دامن عورتوں کو اور پھر چار گواہ (اپنے دعوے پر ) نہ لا سکیں تو ایسے لوگوں کو
اشتی درے لگائے جائیں اور ان کی گواہی آئندہ کبھی نہ قبول کی جائے ).قاضی نے تہمت لگانے کی سزا اجتہاد کر کے اس شاعر پر لاگو کر دی.اگر چہ آئت کریمہ میں خاص
واقعے کا ذکر ہے لیکن اس میں عمومی حالات بھی شامل ہیں.یادر ہے کہ مالکی مذہب کے مطابق کسی پر بہتان لگایا
45
+
Page 64
جائے تو اس کو عدالت میں مقدمہ دائر کرنا لازم ہوتا ہے اور یہی کچھ اس مقدمے میں ہوا.فقہہ اور اصول فقہہ پر کتابیں
قاضی القضاۃ کے عہدے پر فائز ہونے کے بعد نے فقہ کا رخ ہی بدل دیا.اگلے دس سال میں اس
نے طب، فلسفہ اور علم کلام میں متعدد بصیرت افروز کتابیں تصنیف کیں.وہ تمام امور میں اجتہاد سے کام لیتا تھا
اور جدید ملکی تقاضوں کے پیش نظر فروعی مسائل میں اپنے اجتہاد سے فیصلے کرتا تھا.اس اجتہاد کی وجہ سے اسے ملک گیر
شہرت حاصل ہوئی.چنانچہ خلیفہ ابو یعقوب یوسف بن عبد المومن کی 1184ء میں وفات کے بعد جب اس کا بیٹا
ابویوست یعقوب (المحصور ) تخت نشین ہوا تو اس نے ملک کے تمام فقہاء کو حکم دیا کہ کسی امام یا مجتہد کی تقلید نہ کریں
بلکہ خود اپنے اجتہاد سے فیصلہ کریں.چنانچہ تمام عدالتوں میں فروع فقہ کی پابندی اٹھادی گئی اور جو فیصلہ کیا جاتا وہ
قرآن مجید، حدیث، اجماع اور قیاس کی مدد سے ائمہ فقہ کی آراء کی روشنی میں کیا جاتا.فقہ اور اصول فقہ پر نے آٹھ گراں قدر کتا بیں تصنیف کیں.ان میں بداية المجتھد کو خاص
مقبولیت حاصل ہوئی اور اس کی شخصیت چاند ستاروں کی طرح جگمگانے لگی.اس کے علاوہ خلیفہ منصور نے اس کو اپنا
مشیر خاص مقرر کیا ، وہ اکثر فرصت کے اوقات میں دوستانہ ماحول میں اس سے علمی مسائل پر گفتگو کرتا اور اس کے
صائب مشوروں سے خاطر خواہ فائدہ اٹھاتا تھا.اس یا ہمی انس و مودت کی بناء پر خلیفہ منصور کو برادر من کہہ
کر مخاطب کرتا.فقہ اس علم کو کہتے ہیں جس میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں مختلف مسائل کے متعلق احکام صادر کئے جائیں،
اس لئے ضروری ہے کہ جو شخص فقیہ ہو وہ قرآن اور حدیث کا بھی پورا عالم ہو.اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی لازم ہے کہ
فقیہ کو قانونی مہارت کے علاوہ دنیاوی معاملات کا بھی تجربہ ہو اور الجھے ہوئے معاملات و مسائل کو شریعت کے مطابق
سلجھانے کی اہمیت رکھتا ہو.فقدان احکام شرعیہ کا بھی نام ہے جن کا تعلق انسان کے ظاہری اعمال سے ہے.احکام سے مراد وہ عملی مسائل
ہیں جو انسان کو روزمرہ کی زندگی میں پیش آتے ہیں.خواہ وہ مسائل عبادات (نماز، روزه، حج ) یا معاملات (خرید و
فروخت، ٹھیکہ، شرکت ) سے متعلق ہوں.گویا روز مرہ زندگی کے مسائل شرعی سند کے ساتھ پیش کرنے اور ان پر عمل
در آمد کرنے کی تلقین کرنے والے علم کا نام فقہ ہے.فقہ کا اطلاق دینی اور دنیاوی دونوں قسم کے مسائل پر ہوتا ہے اس
لئے فقہ کو دو بڑی قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے.اول عبادات یعنی دینی امور ( نماز، زکوۃ، روزہ ، حج کے احکام کی
46
Page 65
تفصیل) - دوم دنیا دی امور ( عقوبات یعنی حدود تعزیرات ، مناکحات یعنی نکاح خلع ، ایلاء ، ظہار اور معاملات بیع :
شرا، اجاره، ٹھیکہ، عاریت، امانت ، ضمانت ، شرکت معه لحت شفعه ) وغیرد کا تعلق چونکہ مالکی مسلک سے تھا اور وہ لکی مسلک کے مطابق قاضی کی حیثیت سے فرائض انجام دیتا
تھا اس لئے یہاں امام مالک کے مختصر حالات پیش کئے جاتے ہیں.امام مالک مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے ، تمام
زندگی مدینہ میں رہے اور وہیں مدفون ہوئے.وہ مدینہ کے معزز امام ، فقیہ اور محدث امام شافعی کے استاد تھے.علم
حدیث میں ان کی کتاب موطا کے متعلق امام شافعی نے فرمایا ہے کہ کتاب اللہ کے بعد روئے زمین پر امام مالک کی
کتاب سے زیادہ صحیح کوئی اور کتاب نہیں ہے.امام مسائل کے استخراج کے لئے صرف قرآن اور حدیث پر اعتماد
رکھتے تھے اور جس حدیث کی سند وہ صحیح جانتے اس سے استدلال فرماتے تھے خواہ اس روایت کو صرف ایک راوی نے
ہی روایت کیا ہو.وہ اقوال صحابہ کو قابل سند قرار دیتے تھے اور نص کی عدم موجودگی میں اپنے اجتہاد کے مطابق
فتوی دیتے تھے.جب ان کو کسی مسئلہ کے متعلق علم نہ ہوتا تو اس کے متعلق مسئول سے کہہ دیتے لا ادری ( میں
نہیں جانتا.مالکی مذہب پورے حجاز میں پھیلا ہوا تھا لیکن بعد میں صرف اندلس الجزائر، تونس، طرابلس، بالائی
مصر، سوڈان، بحرین میں محدود ہو کر رہ گیا.نے فقہ پر 8 شاہکار کتابیں قلم بند کیں.بداية المجتهد و نهاية المقتصد، كتاب لمقدمات
الفقه خلاصه المستقى للغزالي في اصول فقه، اسباب الاختلاف، الدروس الكاملة في الفقه.مقاله
في الضحايه، فرائض السلاطين والخلفاء، كشف عن المنا هيج الادلة.کشف کا جرمنی زبان میں ترجمہ میکس میولر (Max Muller) نے 1859ء میں فصل المقال کے
ہمراہ فلاسفی انڈ تھیولوجی وان ایور روی Philosophie und theologic von Averroes)
کے عنوان سے میونخ سے شائع کیا.علم فقہ پر اس کی معرکتہ الآراء کتاب بداية المجتهد قاہرہ سے آخری
بار 1966ء میں شائع ہوئی تھی.یہ علم الاختلاف کے موضوع پر بے نظیر اور جلیل القدر کتاب ہے.انگریزی میں اس
کا ترجمہ پروفیسر احسن خان نیازی (اسلام آباد) نے دو جلدوں میں کیا ہے.سے قبل یا لعموم فقہ کی کتابوں میں فروعی مسائل جمع کر دئے جاتے تھے اور قاری یہ معلوم نہیں کر سکتا تھا
کہ کس فروعی مسئلے کو کس اصول کے تحت مستنبط کیا گیا ہے.اور کیا بیان کردہ مسئلہ کا کوئی مخالف پہلو بھی ہے یا نہیں؟
اور اگر ہے تو اسے بیان کرنے والا کس اصول سے اخذ کرتا ہے.نے مسئلہ کے موافق اور نالف پہلو بیان کر
کے ہر ایک مذہب کے تائیدی دلائل بیان کئے.اور اگر ان بیان کردہ مسائل میں سے کسی ایک سے بھی اتفاق نہ ہو تو
اس نے اس مسئلہ میں اپنا اجتہاد پیش کر کے اختلاف بیان کو دلائل صحیحہ سے واضح کیا.اس نے قرآن پاک کی دو
47
Page 66
متضاد آیات یا احادیث نبوی ﷺ کو پیش کر کے ان میں مطابقت ثابت کرنے کی کوشش کی.جس سے یہ ثابت ہوتا
ہے کہ آیا ایک حکم ہر چیز پر لاگو ہے یا کہ اس میں مستثنیات (exceptions ) ہیں یا پھر یہ کہ فلاں حکم بالکل مفسوخ
ہو گیا ہے.اگر چہ مالکی مذہب کا پیروکار تھا لیکن اس کے باوجود اس نے مختلف ائمہ مذاہب (امام ابو حنیفہ
امام شافعی ، امام حنبل) کی آراء بالکل غیر جانب داری سے پیش کیں.مالکی مذہب سے تعلق کا اظہار فقط اس وقت
ہوتا ہے جب وہ اپنے مذہب کے بارے میں کسی شرعی مسئلے پر پائے جانے والی دوسرے مذاہب کی آراء سے زیادہ
روشنی ڈالتا ہے.نے بداية المجتهد و نهاية المقتصد ) Primer for the discretionary
scholar) ایسے شخص کے لئے جو ذاتی کوشش ( اجتہاد ) کرنا چاہتا ہے ، 1167ء میں مکمل کی ، ما سواحج کے باب
کے جو 1188ء میں لکھا گیا تھا.اس کتاب کا تعلق ادب کی اس شاخ (genre ) سے ہے جس کو علم الاختلاف کہا
جاتا ہے.کتاب میں جملہ موضوعات پر مختلف مذاہب کی آراء پیش کی گئی ہیں اور فقہاء کے مابین اختلاف
( controversy ) اور ان کے دلائل پر سیر حاصل بحث کی گئی ہے.اس کتاب کو فقہی کتابوں میں نمایاں مقام
حاصل ہے.اس کے مطالعہ سے اجتہاد کی قوت اور استعداد میں خاطر خواہ اضافہ ہوتا ہے.یادر ہے کہ اجتہاد صرف
فقہی مسائل میں کیا جاتا ہے یعنی جب قرآن اور حدیث کسی مسئلے پر خاموش ہوں
تو اجتہاد کر کے مسئلے کا حل نکالا جاتا
ہے.نے اس کی تصنیف کی غرض و غایت بیان کرتے ہوئے کہا ہے:
اس کتاب کی غرض یہ ہے کہ اگر انسان لغت اور اصول فقہ سے بقدر ضرورت واقف نہ ہو تو اس کے مطالعہ
سے اس میں اجتہاد کی قوت پیدا ہو جائے.اور اسی وجہ سے ہم نے اس کتاب کا نام بداية المجتھد رکھا کیونکہ
اس کے بغور مطالعے سے ( انسان میں ) اجتہاد کی استعداد پیدا ہو سکتی ہے.ہمارا مقصد اس کتاب سے یہ ہے کہ ہم.شریعت کے متفق علیہ اور مختلف علیہ احکام کے مسائل بیان کر دیں، کیونکہ ان دونوں قسم کے مسائل کی واقفیت کے
بعد ہی کوئی مجتہد اس اصول کو جان سکتا ہے جس کے ذریعے وہ پیش آمد اختلاف کو رفع کر سکتا ہے.اگر ان مسائل کی
واقفیت کے ساتھ ساتھ فقہاء کے اختلاف کے علل و اسباب بھی ( انسان کے ) ذہن نشین ہو جائیں تو انسان ہر جدید
حادثے کے متعلق شرعی فتوی دینے کے قابل ہو سکتا ہے.اس کتاب کی تین خصوصیات ہیں:
(1) بداية کے مضامین کی ترتیب دیگر کتب فقہ کی ترتیب سے مختلف ہے.مثلاً عبادات کے بعد کتاب
الجہاد کو کتاب الایمان اور معاملات سے مقدم رکھا گیا ہے کیونکہ کے نزدیک جہاد کا مرتبہ عبادات کے بعد
48
Page 67
سب سے مقدم ہے.اسی طرح کتاب الاشربہ اور کتاب الضحایا کی معاملات سے الگ کر دیا گیا ہے کیونکہ اسلام میں
ان چیزوں کی حیثیت خانو کی ہے.(2) اس کتاب کے مطالعے سے قاری میں اجتہاد کی قوت و استعداد میں خاطر خواہ اضافہ ہوتا ہے.سے قبل فقہاء کا کام صرف یہ تھا کہ وہ اپنے امام کی رائے کی تائید لازما کرتے تھے چنانچہ اپنے امام کے قول کو صحیح
ثابت کرنے کے لئے ہر قسم کے رطب و یابس فراہم کئے جاتے تھے جس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ فریق اپنے اپنے امام کے
مسلک کے ساتھ چمٹا رہتا.اس طرح ان کے ذہنوں میں جلا نہیں پیدا ہو سکتی اور نہ دو خالی الذہن ہو کر یہ فیصلہ کر
سکتے کہ حق کے ساتھ کون ہے اور باطل پر کون ہے.نے یہ کتاب تالیف کر کے ذہنوں کے اس دھارے
کو بدلاء کورانہ تقلید کے انداز کو تہ و بالا کیا اور اذہان میں نئے انداز پر سوچنے کی اہلیت پیدا کی.(3) فقہ کی کتابوں میں عموماً فروعی مسائل جمع کر دئے جاتے ہیں.قاری یہ معلوم نہیں کر سکتا کہ کسی فردی
مسئلے کو کس اصول کے تحت مستنبط کیا گیا ہے اور مسئلے کا کوئی مخالف پہلو بھی ہے یا نہیں.اگر ہے تو اسے بیان کرنے
والے نے کس اصول سے وضع کیا ہے.نے بدایة میں اس مقلدانہ طرز کو ترک کر کے نیا اسلوب اختیار
کیا.اس نے ہر مسئلہ کے مخالف اور موافق پہلو بیان کر کے ہر مذہب کے تائید کی دلائل بیان کئے اور ساتھ ساتھ تر
جیجی مذہب کی نشاندہی بھی کی.بیان کردہ مسائل میں سے کسی بھی مسئلہ سے عدم اتفاق کی صورت میں اس نے اس
مسئلہ میں اپنا اجتہاد پیش کر کے اختلاف بیان کو دلائل سے واضح کیا ہے.پروفیسر مانٹ گھر کی واٹ نے کتاب کے مضامین کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے:
The book deals with the "differences" between the various legal schools
and pays special attention to the types of arguments used by each to
justify its particular decisions.(14) کی وسعت نظر کا اظہار بدایہ کے ہر صفحے سے ہوتا ہے اس نے معروف اور غیر معروف ہر قسم کے ائمہ
کے نظریات اس کتاب میں پیش کئے ہیں.امام مالک کے اصحاب میں سے ابن القاسم، اشہب ، سحنون، ابن
الماجشون نیز امام ابوحنیفہ پھر امام شافعی کے اصحاب عطار بن دینار، ابو ثور، امام ثوری، اوزاعی ، امام احمد حنبل ، امام
داؤد ظاہری، فقیہ ابواللیث ابن ابی لیلی ، ابن جریر طیری غرض تابعی اور غیر تابعی ہر قسم کے ائمہ کے اقوال کتاب میں
نقل کر کے ہر ایک کے دلائل بھی واضح طور پر بیان کئے ہیں.اگر کسی مسئلے میں صحابہ کا اختلاف ہے تو اختلاف کو
مع وجہ کے بیان کیا ہے.انہی خصوصیات کی وجہ سے بدایہ بہت مقبول ہوئی اور اجتہاد میں کا اعلیٰ مقام
49
Page 68
مخالف و موافق سب نے تسلیم کیا.عورت کی امامت نے عورت کی امامت کے متعلق اختلافات پیش کرنے کے بعد لکھا ہے: و شذا ابو نورا
والطبرى فاجازا اما منها على الاطلاق - ابو ثور اور طبری جمہور سے الگ ہیں اور اس بات کے قائل ہیں کہ
عورت علی الاطلاق امامت کر سکتی ہے عورتوں اور مردوں دونوں کی ہدایتہ المجتهد جلد اول صفحه 185).استحقاق قضاۃ اور حاکمیت کے بیان میں عورت کے قاضی اور حاکم ہونے کے متعلق اختلافات تحریر کرنے کے
بعد این رشد نے تحریر کیا ہے: " قال الطبریي يجوز ان تكون المرآة حاكما على الاطلاق في كل
عورت علی الاطلاق ہرشئے میں حاکم ہو سکتی ہے ( یعنی دیوانی اور فوجداری کی کوئی تخصیص نہیں) بلکہ وہ بادشاہ
بھی ہو سکتی ہے".( بداية المجتهد جلد دوم صفحہ 277) کے محاکمہ کی مثال.فقہاء میں ایک قابل ذکر اختلاف یہ ہے کہ ولی کے بغیر نکاح جائز ہے یا نہیں ؟ حضرت امام مالک اور حضرت
امام شافعی" کا مسلک یہ ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوسکتا.حضرت امام ابو حنیفہ، امام زفر ، امام شعمی اور
امام زہری کے نزدیک جب کوئی عورت اپنا نکاح ولی کی اجازت کے بغیر کسی ایسے شخص سے کر لے جو اس کے معیار
کے مطابق ہو تو جائز ہے.داؤد ظاہری نے باکرہ کے نکاح کے لئے ولی کا ہونا ضروری قرار دیا ہے لیکن شیبہ بغیر ولی
کے نکاح کر سکتی ہے.منکرین حضرت ابن عباس سے مروی حدیث کو اپنے موقف کے حق میں پیش کرتے ہیں اور
ظاہر ابھی اس حدیث کے ظاہر الفاظ سے استدلال کرتے ہیں.کہتا ہے قرآنی آیات کا طرز خطاب کسی فریق کی حجت نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ محکم نہیں ہے بلکہ مجمل
ہے.نہ ہی شارع (پیغمبر) نے اپنے طرز عمل سے اس کی تشریح کی ہے.حضرت ابن عباس کی حدیث سے بھی
ظاہریہ کی تائید ہوتی ہے.اگر اس مسئلہ پر غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ بلوغت کی عمر کو پہنچنے پر عورت کو تصرف مال کا
حق شرعاً حاصل ہو جاتا ہے.یہ نظیر یہ ثابت کرنے کے لئے کافی ہے کہ عورت کو عقد نکاح کا حق بھی ملنا چاہئے، ولی کو
زیادہ سے زیادہ نگرانی اور شیخ کا حق دیا جا سکتا ہے.پھر اگر شرعا ولی کی موجودگی نکاج کے لئے شرط ہوتی تو پیغمبر اس
مسئلہ کی وضاحت فرما دیتے یعنی وہ اصناف اولیاء اور ان کے مراتب اور اختیارات کی تشریح بھی کر دیتے.(بداية
المجتهد جلد دوم صفحه 8-7 )
50
Page 69
اختلاف کی ایک مثال
بداية المجتھد میں ایک باب جہاد پر ہے.اس میں اس بات پر بحث کی گئی ہے کہ جنگ کے دوران دشمن
کو نقصان اور اس کو جسمانی زخم یا اس کی جائداد یا اس کی آزادی کا سلب کیا جاتا ( یعنی اس کو غلام بنا لینا ) کس حد تک
جائز ہے ؟ اجماع ائمہ یہ ہے کہ ایسا نقصان مشرک مرد، عورت جوان ، بوڑھے، معروف یا غیر معروف افراد کو
پہنچایا جا سکتا ہے.صرف راہبوں کے بارے میں مختلف رائے ہیں، کچھ کا کہنا ہے کہ ان کو قید نہ کیا جائے ، ان کو امن
میں رہنے دیا جائے ، ان کو غلام نہ بنایا جائے.اپنی اس رائے کے حق میں وہ حدیث نبوی ﷺ پیش کرتے ہیں جس
میں حضور پاک ﷺ نے فرمایا ان کو امن میں رہنے دواور وہ چیز بھی جس کے لئے انہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا
ہے.نیز وہ لوگ اپنے موقف میں حضرت ابو بکر صدیق کا عملی نمونہ بھی پیش کرتے ہیں.اکثر علما اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ قیدیوں کے ساتھ سلوک کے بارے میں اسلامی ریاست کے
سر براد (امام یا خلیفہ ) کو کئی اختیارات حاصل ہیں.وہ ان کو معاف کر سکتا ہے ، ودان کو غلام بنا سکتا ہے، وہ ان کو قتل
کرسکتا ہے وہ ان کو ان کی دینی پر با کرسکتا ہے یا ایسا شخص ہی بن کر ملک میں رہ سکتا ہے.آخری صورت میں
قیدی کو جز یہ دینا لازمی ہوگا.بعض علما کا کہنا ہے کہ قیدیوں کو بھی قتل نہ کیا جائے.الحسن ابن محمد اتمیمی کے مطابق صحابہ
کرام کا اس امر پر اجماع تھا.یہ اختلاف اس لئے پیدا ہوا : اول قرآن کریم کی آیات اس ضمن میں بظاہر متضاد ہیں.دوم رسول کریم ہوتا ہے
اور خلفاء راشدین کے طرز عمل میں بظاہر تناقض ہے.سوم قرآن پاک کی آیات کی تعبیر رسول پاک میں کے اعمال
سے بظاہر میل نہیں کھاتی ہے.قرآن پاک کی سورۃ نمبر 47 آیت نمبر 4 میں ارشاد ہوا ہے: فاذا لقيتم الذين
کفر و افضرب الرقاب، حتى اذا اثخنتموهم فشد و الوثاق - (ترجمہ : موجب تمہارا کفار سے مقابلہ
ہو جائے تو ان کی گردنیں مارو ، یہاں تک کہ جب تم ان کی خوب خون ریزی کر چکو تو خوب مضبوط باندھ لو ( قیدی
بنالو ) ( ترجمہ مولانا اشرف علی تھانوی ، تاج کمپنی ، لاہور ).قرآن کی سورۃ نمبر 8 ، آیت نمبر 67 میں ارشاد ہوا ہے:
ما كان لنبى ان يكون له اسرئ حتى ينخن في الارض (ترجمہ: نبی کی شان کے لائق نہیں کہ ان
کے قیدی باقی رہیں ( بلکہ قتل کر دئے جائیں) جب تک کہ وہ زمین میں اچھی طرح ( کفار کی ) خون ریزی نہ کر
لیں.( ترجمہ مولانا اشرف علی تھانوی صفحہ 167) نیز جس موقعے پر یہ آیت نازل ہوئی (یعنی جنگ بدر کے قیدی)
اس سے مستنبط ہوتا ہے کہ قیدیوں
کو قتل کر دینا بہتر ہے بجائے ان کو غلام بنانے کے.خود آنحضور ﷺ نے میدان
جنگ کے باہر قیدیوں
کو بعض دفعہ قتل فرمایا لیکن بعض دفعہ ان کو معاف بھی فرما دیا.اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ
51
Page 70
نے اجماع کیا کہ اہل کتاب کے مرد اور عورتیں غلام بنائے جا سکتے ہیں.وہ لوگ جن کی رائے یہ ہے کہ آیت کریمہ 47:40 ) جو قتل کی ممانعت کرتی ہے وہ سنت نبوی کی تنسیخ کرتی ہے ان
کی رائے میں قیدیوں کوقتل نہیں کیا جاسکتا.اس کے برعکس بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ چونکہ نبی پاک نے قیدیوں کو قتل
کیا کرتے تھے، وو در اصل آیت 47:4 کے حق میں تصدیق ہے.اس لئے نبی کریم نے اگر بدر کے قیدیوں کو قتل نہیں فرمایا
تو وہ مناسب ہے، کوئی شکایت والی بات نہیں.یوں ایسے لوگ تسلیم کرتے ہیں کہ قیدیوں کا قتل کرنا جائز ہے (15).اختلاف کی ایک اور مثال نے لکھا ہے کہ دشمن کی جائیداد ( جیسے عمارتوں ، مویشیوں ، زرعی فصلوں ) کو کسی قسم کا نقصان پہنچایا
جا سکتا ہے؟ اس بارے میں مختلف آراء ہیں.مالک بن انس نے درختوں ، پھلوں اور عمارتوں کو گرانے کی اجازت
دی ہے لیکن مویشیوں کو قتل کرنے کی اور کھجور کے درختوں کو جلانے کی اجازت نہیں دی ہے.اوزاعی نے پھلوں
والے درختوں اور عمارتوں کے گرانے کی مخالفت کی ہے چاہے ایسی عمارتیں گرجے ہی کیوں نہ ہوں.امام شافعی نے
فرمایا ہے کہ عمارتیں اور درخت جلائے جا سکتے ہیں بشرطیکہ دشمن ان کو قلعوں کے طور پر استعمال کر رہا ہو.اگر ایسا نہیں
تو عمارتوں کا گرانا اور درختوں کا کا ثنا قابل سرزنش ہے.اس اختلاف کی کئی وجوہات ہیں.مثلاً حضرت ابو بکر کی عملی نمونہ آنحضرت ﷺ کی سنت کے خلاف تھا.ایک
مستند روایت کے مطابق نبی پاک ﷺ نے قبیلہ بنونضیر کے کھجور کے درختوں کو آگ لگا کر جلا دیا تھا.جبکہ حضرت
ابو بکرہ کا نا قابل تردید حکم یہ ہے کہ درخت مت کا اٹو اور عمارتوں کومت گراؤ.بعض لوگوں کا خیال ہے کہ حضرت ابو بکر
نے اگر ایسا فرمایا تو صرف یہ جان کر کہ نبی پاک کا عملی نمونہ منسوخ ہو چکا ہے کیونکہ ابو بکرے کے لئے یہ کیسے ممکن تھا کہ ود
نبی کریم کی سنت کا علم رکھتے ہوئے تردید کرتے.بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی پاک ﷺ کا یہ عمل صرف اور صرف
بنونضیر کے قبیلہ کے لئے تھا کیونکہ ان لوگوں نے نبی پاک پر حملے میں پہل
کی تھی.جو لوگ ایسے دلائل پیش کرتے ہیں
وہ ابو بکر کے نقطہ نظر سے اتفاق کرتے ہیں.اس کے برعکس ایسے لوگ بھی ہیں جو سراسر نبی پاک ﷺ کے عملی نمونے
پر انحصار کرتے ہیں.ان کا نظریہ یہ ہے کہ کسی کے قول کو اس کے اپنے عملی نمونے کے برعکس دلیل کے طور پر پیش
کرنا صحیح نہیں ہے.اس لئے ان کے نزدیک درختوں کا جلاد دینا جائز ہے.امام مالک نے مویشیوں اور درختوں میں فرق بیان کیا ہے.ان کے نزدیک مویشیوں
کا قتل اذیت دینے کے
مترادف ہے، اس لئے یہ قطعی طور پر منع ہے.مزید برآں آنحضور ﷺ نے کبھی بھی جانوروں کو قل نہیں فرمایا تھا.52
Page 71
اختلاف کی مثال نکاح سے متعلق
نکاح کی تین بنیادی شرائط ہیں : ولی گواہ اور حق مہر.ولی کے کیا اوصاف ہونے چاہئیں؟ تمام فقہا ، اس بات
پر متفق ہیں کہ دلی مسلمان بالغ مرد ہونا چاہئے.لیکن تین اشخاص کے متعلق اختلاف ہے: غلام، فاسق اور بیوقوف
( جو نفع و نقصان میں فرق نہ کر سکے ).غلام کے متعلق اکثر فقہاء کا مذہب یہ ہے کہ اس کی ولایت درست نہیں ہے
لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک درست ہے.(یہ حکم آج کے دور پر چسپاں نہیں ہوتا کیونکہ غلامی غیر قانونی قراردی
جاچکی ہے).رشد یعنی نیکی کے متعلق اصحاب مالک کا مذہب یہ ہے کہ یہ امر ولایت کے لئے شرط نہیں ہے.ان
کے شاگردوں میں سے اشہب اور ابو مصعب اس روایت کے حامی ہیں.اور یہی مذہب امام ابو حنیفہ گا ہے.لیکن
امام شافعی کے نزدیک رشد بھی گواہ کے لئے ایک ضروری شرط ہے.سمجھداری سے مراد وہ صفت ہے جس کے ماتحت
کوئی شخص نفع اور نقصان میں تمیز کر سکتا ہے.وجه اختلاف اس اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ آیا نکاح کی ولایت مال کی ولایت کے مشابہ ہے یا نہیں ؟ جن کے
نزدیک رشد ولایت نکاح میں ضروری ہے لیکن ولایت مال میں ضروری نہیں انہوں نے ولایت مال کے لئے رشد کا
پایا جانا ضروری نہیں قرار دیا.کے نزدیک ولایت مال اور ولایت نکاح دونوں کے لئے رشد کا پایا جانا
ضروری ہے لیکن ولایت نکاح اور ولایت مال دونوں میں رشد کے مدارج میں فرق کرنا پڑے گا.ولی کے عادل
ہونے کے بارے میں اختلاف اس وجہ سے ہے کہ ولی کے غیر عادل ہونے کی صورت میں اس بات کا اندیشہ باقی
رہتا ہے کہ وہ ایسا رشتہ تجویز کر دے جو غیر مناسب ہو اور لڑکی کے معیار کے مطابق نہ ہو.ولایت نکاح کا فریضہ
تقاضہ کرتا ہے کہ ولی عادل ہو.کہتے ہیں کہ ولایت نکاح کے لئے جن اوصاف کی ضرورت ہے ان میں
عدالت کا شمار نہیں ہوتا کیونکہ معیاری رشتہ تلاش کرنے کا اصل محرک تو انسان کا یہ احساس ہے کہ لوگ اسے یہ طعنہ نہ
دیں کہ اس نے ایسا رشتہ تلاش کیا جو اس کے شایان شان نہیں ہے.عادل سے مراد ایسا شخص جو معاشرے میں عزت
کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہو.(15)
بغیر مہر کے نکاح
اس بات پر سب فقہاء کا اتفاق ہے کہ ایسا نکاح جس میں مہر مقرر نہ کیا گیا ہو جائز ہے.یعنی نکاح کی صحت
کے لئے مہر کا مقرر کرنا ضروری نہیں ہے.البتہ رخصت کے بعد مہر واجب ہو جائے گا.اللہ تعالی کا ارشاد ہے
لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسو هن او تفرضوا لهن فريضة (بقرة آيت : 236)
53
Page 72
( ترجمہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہو گا اگر تم بیویوں کو ایسی حالت میں طلاق دے دو جبکہ تم نے ان کو چھوا تک نہ ہو اور نہ ہی
مہر مقرر کیا ہو.) اس بارے میں دو مواقع پر اختلاف کیا گیا ہے.اول : جب بیوی مہر مقرر کرنے کا مطالبہ کرے
اور میاں بیوئی کا مقدار مہر میں اختلاف ہو.دوم: جب خاوند فوت ہو جائے اور اس نے نکاح کے موقعے پر مہر مقرر نہ
کیا ہو.مسئلہ اول کے متعلق فقہاء کے ایک گروہ کا مذہب یہ ہے کہ اس کا مہر مثل مقرر کیا جائے گا.اگر خاوند اس
اختلاف کے دوران بیوی کو طلاق دے دے تو اس صورت میں بعض کے نزدیک اس کا نصف مہر ادا کرے اور بعض
کے نزدیک اس کا کوئی مہر نہیں ہے.کیونکہ نکاح کے موقعے پر اس کا کوئی مہر مقرر نہیں تھا.یہ مذہب امام ابو حنیفہ اور
ان کے اصحاب کا ہے.امام مالک کے نزدیک مسئلہ اول میں خاوند کو تین اختیارات دئے جائیں گے.اول بیوی کو
مہر مقرر کئے بغیر طلاق دے دے.دوم عورت کے مطالبہ کے مطابق اس کا مہر مقرر کر کے سوم مہر مثل مقرر کرے.وجه اختلاف یہ بحث اللہ تعالی کے ارشاد ( سورة بقرة ، آیت : 236) کے سلسلے میں اختلاف کی بناء پر
ہے.بعض کے نزدیک یہ آیت مہر کے سقوط کے متعلق ایک عام حکم بیان کرتی ہے خواہ طلاق کی وجہ مہر مقرر نہ کرنے کا
معاملہ ہو یا کوئی اور وجہ ہو.نیز اس آیت میں گناہ کی نفی سے مراد یہ ہے کہ طلاق دینے والے پر مہر واجب نہیں ہے یا
اس کا کوئی اور مطلب ہے ؟ اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک ظاہر مفہوم تو یہی تقاضا کرتا ہے کہ
ایسی صورت میں طلاق دینے والے پر مہر واجب نہیں ہوتا جیسا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے: و متعوهن على الموسع
قدره وعلى المقتر قدره ( سورۃ بقرہ، آیت:236) ( ترجمہ : اور چاہئے کہ تم انہیں مناسب طور پر کچھ
سامان دے دو.دولت مند پر اس کی حیثیت کے مطابق اور نا دار پر اس کی حیثیت کے مطابق ).کہتے ہیں
کہ میرے نزدیک اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں کہ اگر کوئی شخص مہر مقرر کرنے سے قبل طلاق دے دے تو اس پر
کچھ واجب نہیں ہے.مزید فرماتے ہیں کہ جولوگ اس بات کے قائل ہیں کہ اگر کوئی شخص تعلقات زوجیت سے قبل اپنی
بیوی کو طلاق دے دے جبکہ نکاح کے وقت اس کا حق مہر مقرر ہو چکا ہو تو اس صورت میں خاوند پر نصف مہر کے علاوہ
کچھ امداد بھی کرنی ہوگی جو نقد مال یا کپڑوں کی صورت میں ہو سکتی ہے.اور وہ لوگ جو اس بات کے قائل ہیں کہ جس
نکاح میں مہر مقرر نہیں ہوا ان کے نزدیک مہر مثل واجب ہو جاتا ہے ان پر یہ واجب ہے کہ وہ ایسے نکاح میں اگر
مجامعت سے قبل طلاق ہوئی ہو تو ز 1 کے سامان کے علاوہ مہرشل کا نصف بھی ادا کریں کیونکہ آیت سے صرف اتنا ثابت
ہوتا ہے کہ مہر مقرر کرنے سے قبل طلاق دی جا سکتی ہے.مہر کے ساتھ ہونے کا براہ راست اس آیت کر نیمہ سے کوئی
تعلق نہیں ہے.54
4
Page 73
مسئلہ دوم : جب خاوند فوت ہو جائے اور اس نے نکاح کے وقت مہر مقرر نہ کیا ہو اور زوجیت کے تعلقات بھی
قائم نہ ہوئے ہوں تو اس صورت میں امام مانگ اور ان کے اصحاب اور اوزاعی کا مذہب یہ ہے کہ اس کے لئے کوئی
مہر نہیں ہے بلکہ اس کی دلداری کے لئے کچھ دے دینا چاہئے.عورت اس کی میراث میں بھی شریک ہوگی (16).غرضيك بداية المجتهد بلحاظ اسلوب تحریر، ترتیب مضامین، جمع اقوال ائمہ قوت فقلبتہ ایک بے مثل کتاب
ہے.اگر چہ فقہ کی دوسری کتا بیں بھی اسی طرز پرلکھی گئی تھیں لیکن اختصار کے ساتھ جامعیت کے لحاظ سے اس جیسی کوئی
کتاب نہیں ہے.نے فقہ کے بارے میں جس علمی استدلال اور واقفیت کا ثبوت دیا ہے اور جس طرح اصولی
طرز پر محاکمہ کیا ہے اس کے بعد یہ کہنے میں کوئی مضائقہ نہیں کہ بلا شبہ وہ اپنے زمانے کے مجتہد اعظم تھے.یورپ میں
اگر چہ وہ شارح ارسطو تھے لیکن مسلمانوں کے لئے ان کا ایک تمغہ امتیاز ان کا رتبہ اجتہاد بھی رہا ہے.کا علم کلام
علم کلام فلسفہ کی پیداوار ہے.اندلس میں عام طور پر فلسفہ و منطق کی درس و تدریس کو بہ نظر استحسان نہیں دیکھا
جاتا تھا اس لئے وہاں علم کلام زیادہ ترقی نہیں کر سکا.اس کے باوجود ابن حزم نے فلسفہ و منطق میں کمال پیدا کیا اور علم
کلام پر دو مستند کتابیں لکھیں.اندلس میں اشعری مذہب کے رائج ہونے کے بعد تاویل کی بحث نے وہاں شدت
اختیار کر لی اور مسلمانوں میں دو گروہ پیدا ہو گئے ، ایک تاویل کو جائز اور دوسرانا جائز خیال کرتا تھا.علماے سلف آیات
متشابہات میں تاویل کو نا جائز سمجھتے تھے.لیکن اشاعرہ نے ان میں بڑے شدومد سے تاویل کی.اس اختلاف سے یہ
مسئلہ معرکۃ الآراء بن گیا.در حقیقت تاویل کے پروہ میں ان لوگوں نے اور دوسرے فلسفیوں نے شریعت کی بیخ کنی
شروع کر دی تھی.علم کلام میں اس طرح دو اہم مسئلے پیدا ہو گئے تھے.اول یہ کہ فلسفہ اور شریعت میں با ہمی تعلق کیا ہے؟ دوم
نصوص شرعیہ میں تاویل جائز ہے یا نہیں ؟ فقہاء کا گروہ کہتا تھا کہ فلسفہ کی تعلیم جائز نہیں کیونکہ اس سے عقائد میں
ضعف پیدا ہوتا ہے.دوسرا گروہ کہتا تھا کہ فلفہ عین دین ہے
اور فلسفہ جو عبیر کرتا ہے وہی شریعت کی صحیح تعبیر ہے.جیسا کہ ہر ظاہر کا باطن ہوتا ہے، بعینہ شریعت ظاہر ہے اور فلسفہ باطن.میں یہ دونوں خصوصیات جمع ہوگئی تھیں.ایک طرف وہ مجتہد اور فقیہ اور دوسری طرف محقق فلسفی تھا.وہ
عقل اور مذہب دونوں کو ایک دوسرے کا محمد ومعاون دیکھنا چاہتا تھا.فصل المقال میں فرمایا : جو لوگ فلسفی کہلاتے
ہیں ان سے شریعت کو زیادہ نقصان پہنچا ہے، کیونکہ دوست سے جو تکلیف ملتی ہے وہ دشمن کی دی ہوئی تکلیف سے
55
Page 74
زیاد سخت ہوتی ہے.فلسفہ شریعت کی سہیلی اور اس کی رضاعی بہن ہے اس لئے ایک فلسفی سے جو تکلیف پہنچتی ہے وہ
بہت زیادہ تخت ہوتی ہے، یوں شریعت اور فلسفہ میں باہم جنگ چھڑ جاتی ہے حالانکہ دونوں حقیقت میں با ہم دوست
اور متحد ہیں" (صفحہ 26-25) بعض فلاسفہ نے شریعت میں تاویلیں کر کے اسلام کے عقائد کو مسخ کرنے کی کوشش کی
تھی.فلاسفہ کے علاوہ بعض اہل اسلام نے تاویل کا دروازہ کھول کر خود اپنے آپ کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا تھا،
اس لئے اتنے بہت سے فرقے پیدا ہو گئے تھے.کا کہنا تھا کہ مجتہد میں ذات الفطرة (keen sense of truth) کے علاوه العدلته الشريعة
ethical virtue ) کا ہونا ضروری ہے.تمام لوگ دلائل سے ثبوت ملنے پر یقین نہیں لاتے بلکہ بعض لوگ
الاقاویل المجد لیہ اور بعض خطابیہ سے تصدیق کرتے ہیں.قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے کہ خدا انسانوں سے تین قسم
کے طرز استدلال سے گفتگو کو سحسن جانتا ہے: ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة و
جادلهم بالتي هي احسن (16:125) ترجمہ : آپ اپنے رب کی راہ (دین) کی طرف علم کی باتوں اور
اچھی نصیحتوں کے ذریعہ بلائے ، اور (اگر بحث آن پڑے تو ) ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بحث کیجئے (اس میں
شارت نہ ہو).بھی اگر چہ فلسفی ہونے کے ناطے سے شریعت کے بعض نصوص کی تاویل کو ضروری قرار دیتا تھا لیکن
اس کے لئے اس کے نزدیک شرط یہ تھی کہ ایسا صرف دلوگ کر سکتے ہیں جو صاحب نظر اور ماہر دین ہوں.وہ ہر کس و
ناکس کے لئے تاویل کونا جائز قرار دیتا تھا، اس کے نزدیک عوام کو صرف ظاہری معنوں
کی تلقین کرنی چاہئے.علم کلام پر نے درج ذیل تصانیف عالیہ قلم بند فرمائیں: فصل المقال فيما بين الحكمة و
الشريعة بين الاتصال.ذيل فصل المقال، الكشف عن منا هيج الادله في عقائد الملة
شرح عقيده ابن تومرت الامام المهدي، تهافت التهافت الفلاسفہ - ایک رسالہ اس عنوان پر کہ
عالم کے حدوث کے متعلق فلاسفہ اور متکلمین میں حقیقتاً کوئی اختلاف نہیں.ان معرکۃ الآراء کتابوں میں سے دوکا
خلاصہ یہاں پیش کیا جاتا ہے.فصل المقال
فصل المقال کی مایہ ناز تصنیف ہے.فقہ میں یہ کتاب غیر معمولی سرمایہ خیال کی جاتی ہے.کتاب
کے مطالعہ سے مصنف کی جامع کمالات شخصیت کے بے شمار گوشے سامنے آتے ہیں.در حقیقت یہ کتاب اس کی
شخصیت کی ایسی آئینہ دار ہے جس میں اس کی ندرت فکر اور اسلوب کے گوشوں کا عکس منور نظر آتا ہے.اس کے زور
56
Page 75
علم اور تجر علمی ہی نے تاریخ اسلام میں اس کو قد آور شخصیت کا جائز مقام دلایا تھا.فصل المقال ( فیصلہ کن کتاب ) میں اس موضوع پر اس نے روشنی ڈالی ہے کہ کیا منطق و فلسفہ کی تعلیم جائز ہے
پا نہیں؟ منطق و فلسفہ کے متعلق اس دور میں مسلمانوں میں دو گروہ پیدا ہو گئے تھے.محدثین کا گروہ کہتا تھا کہ ان کی
تعلیم جائز نہیں کیونکہ ان سے مذہبی عقائد میں ضعف پیدا ہوتا ہے.دوسرا گروہ کہتا تھا کہ فلسفہ دین کے عین مطابق
ہے اور شریعت کی وہی تعبیر صحیح ہے جو فلسفہ کرتا ہے، اس لئے کہ ہر ظاہر کا باطن ہوتا ہے اور شریعت ظاہر ہے اور فلسفہ
باطن کا کہنا ہے کہ ان دونوں گروہوں کی رائے ٹھیک نہیں.اس کے نزدیک فلسفہ و منطق کا سیکھنا نہ صرف
جائز بلکہ واجب و مستحب ہے کیونکہ قرآن حکیم میں خدا نے عالم کا ئنات سے اپنے وجود پر استدلال قائم کیا ہے.جیسے
آیات کریمہ: فاعتبروا یا اولی الابصار، فاعتبروا یا اولی الالباب.عربی میں اعتبار اور قیاس ہم معنی لفظ
ہیں یہی وجہ ہے کہ فقہاء اس قسم کی آیات سے قیاس فقہی ثابت کرتے ہیں.اگر ان آیات سے قیاس فقہی کا جواز نکلتا
ہے تو اس سے قیاس برہان کیوں جائز نہیں؟
قیاس کی ایک مثال : حضرت امام ابو حنیفہ نے حضرت امام باقر سے دریافت کیا کہ مرد ضعیف ہے یا عورت ؟
امام باقر نے فرمایا عورت.پھر امام ابو حنیفہ نے سوال کیا وراثت میں مرد کا زیادہ حصہ ہے یا عورت کا ؟ حضرت امام
باقر نے فرمایا مرد کا.اب امام ابو حنیفہ نے کہا کہ اگر میں قیاس لگاتا تو کہتا کہ عورت کو زیادہ حصہ دیا جائے کیونکہ
ظاہری قیاس کی بناء پر ضعیف کو زیادہ ملنا چاہئے.( امام اعظم مطبوعہ فیروز سنز لاہور 1977 صفحہ 28)
جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ فلسفہ سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں اس لئے اس کا سیکھنا حرام ہے، تو پوچھتا ہے
کہ نفع و ضرر سے دنیا کی کون سی چیز مستی ہے؟ غذا کا بل اور اس کی کثرت معدہ میں بار پیدا کرتی ہے، اب
کیا اس بناء پر یہ طبعی قاعدہ بنایا جا سکتا ہے کہ غذا طبی طور پر مصر ہے؟ کیا صرف فلاسفہ ہی بے دین ہوتے ہیں؟ کیا
فقہاء کبھی گمراہ نہیں ہوتے؟ تجربہ بتلاتا ہے کہ فلسفہ سے زیادہ فقہ سے بے دینی کی اشاعت ہوتی ہے لیکن فرق یہ ہے
کہ فقیہ کی بے دینی پر اس کا جبہ و عمامہ پردہ ڈالے رکھتے ہیں.نصوص قرآنی کی تاویل جائز ہے یا نہیں؟ اس کے متعلق مسلمانوں میں دو گروہ تھے ، ایک تاویل کو نا جائز سمجھتا تھا
اور دوسرا اس کا قائل تھا.سب سے پہلے اشاعرہ نے آیات متشابہات میں تاویل کی اور اس کے بعد یہ مسئلہ معرکتہ
الآراء بن گیا.کے زمانہ میں فلسفہ و مذہب میں باہمی تعلق کے مسئلہ کی طرح یہ مسئلہ بھی ارکان دین میں شمار کیا
جاتا تھا.نے کہا کہ تاویل جن نصوص میں جائز ہے وہ صرف ان لوگوں کے لئے مخصوص ہے جو راسخ فی العلم
ہیں.عام لوگوں کو ظاہری معنی کی تلقین کرنی چاہئے.مثلاً اگر عوام سے یہ کہا جائے کہ خدا ہے مگر اس کا کوئی مقام نہیں، نہ
57
Page 76
جہت ہے ، وہ قیامت کے روز ہی دکھائی دے گا مگر اس کا جسم نہیں ہے تو اس قسم کا وجود ان کے ذہن میں سانہیں سکتا.تاویل کے شرعی اصول کیا ہیں؟ تاویل کی ضرورت بیان کرتے ہوئے اس نے کہا: "شریعت نے جن باتوں
میں واضح حکم دینے میں خاموشی اختیار کی ہے اس میں اور برہان عقلی میں کوئی تناقض نہیں ہے.لیکن اگر شریعت نے
ان
کو بیان کیا ہے اور اس بیان کے ظاہری معنی بربان علی کے موافق ہیں تو اس میں کوئی بحث نہیں ہونی چاہئے.ہاں
اگر وہ برہان عقلی کے خلاف ہیں تو ان کی تاویل کرنی چاہئے.تاویل کے معنی یہ ہیں کہ لفظ کے حقیقی معنی کو چھوڑ کر
مجازی معنی لئے جائیں.لیکن اس کے ساتھ اہل عرب نے مجازی معنی لینے کے جو اصول وضع کئے ہیں ان میں خلل
واقع نہیں ہونا چاہئے، مثلاً یہ کہ ایک چیز کو بول کر اس کے مشابہ یا اس کے سبب یا عوارض وغیرہ مراد لئے جائیں.فقہا بہت سے احکام شریعہ میں ایسا ہی کرتے ہیں، تو ایک فلسفی کے لئے ایسا کرنا اور بھی زیادہ مستحب ہے.مسلمانوں
کا اس امر پر اتفاق ہے کہ نہ تو شریعت کے تمام الفاظ کو ظاہری معنوں پر محمول کرنا چاہئے ، اور نہ ہی تاویل کے ذریعہ
ان کے تمام معنوں کو چھوڑ دینا چاہئے.ہاں اس بات میں اختلاف ہے کہ کن الفاظ کی تاویل کرنی چاہئے اور کن
الفاظ کے ظاہری معنی لینے چاہئیں."
مثل اشاعرہ آیت استواء اور حدیث نزول کی تاویل کرتے ہیں اور حنابلہ ان کے ظاہری معنی مراد لیتے ہیں "
قرآن مجید پر اگر غور کیا جائے تو اس میں جمہور کی تعلیم کے تین طریقے موجود ہیں، جو اکثر لوگوں کی تعلیم میں مشترک
ہیں، ان طریقوں سے بہتر طریقے کہیں اور نہیں پائے جاتے.اس لئے جس شخص نے ایسی تاویل سے جو بذات خود
واضح نہ ہو ان طریقوں میں تحریف کی یا سب پر اس کو ظاہر کر دیا، اس نے اس کی حکمت کو برباد کر دیا اور شریعت نے
انسانی سعادت کا جو مقصد سامنے رکھا تھا ، اس کو ضائع کر دیا.صدر اول اور اس کے بعد کے مسلمانوں کے حالات
کے موازنہ سے یہ بات بخوبی ثابت ہوتی ہے.صدر اول کے مسلمانوں کو جو فضیلت اور تقویٰ حاصل تھا اس کی وجہ
یہی تھی کہ وہ تاویلات نہیں کرتے تھے اور جو لوگ تاویل سے واقف تھے وہ اس کی تصریح کو جائز نہیں سمجھتے تھے.اس
کے بعد کے مسلمانوں نے تاویل کا استعمال کیا تو ان کا تقویٰ کم ہو گیا، اختلافات بڑھ گئے اور باہمی محبت زائل ہو
گئی."
كشف المنا هيج
کشف الادلہ میں نے اپنے دور کے چار مشہور فرقوں یعنی اشاعرہ معتزلہ، باطنیہ اور حشویہ کے
عقائدہ پر تنقید کر کے ان کے طریق استدلال کی غلطی بیان کی ہے.پھر اثبات باری تعالی ، توحید، صفات باری،
حدوث عالم ، بعثت انبیاء، جور و عدل اور معاد کی حقیقت اور ان پر عقلی ونقلی دلائل پیش کئے ہیں.اس نے بتایا ہے کہ
58
Page 77
ان فرقوں نے جو عقائد تاویل کے ذریعہ ایجاد کئے ہیں وہ صریح غلط ہیں.ان فرقوں میں سے معتزلہ کے عقائد پر اس
نے بہت کم بحث کی ہے کیونکہ اندلس میں ان کا صحیح مسلک جاننے کے لئے ان کی کوئی کتاب یا رسالہ دستیاب نہیں
تھا.باطنیہ کے متعلق بھی کچھ اظہار خیال نہیں کیا.حشویہ کے متعلق صرف اتنا لکھا کہ شرعی عقائد میں ان کے نزدیک
عقل کو کوئی دخل حاصل
نہیں ہے.پھر قرآن مجید کی متعدد آیات سے ثابت کیا کہ خدا نے اپنے وجود پر بہت سے عقلی
دلائل پیش کئے ہیں.صوفیہ کے متعلق لکھا کہ ان کا مسلک قیاس سے مرکب نہیں ہے بلکہ ان کے نزدیک علم و معرفت
کا طریقہ یہ ہے کہ قلب کو عوارض شہوانیہ سے پاک کرکے مطلوب پر غور و فکر کیا جائے.اس نقطہ نظر کے ثبوت میں وہ
قرآن حکیم کی آیات بطور دلیل پیش کرتے ہیں.اگر اس طریقہ کو صحیح تسلیم کر لیا جائے تو پھر بھی یہ تمام انسانوں کے
لئے نہیں ہو سکتا.اس سے نظر نی طریقہ بالکل غلط ثابت ہو جائیگا، حالانکہ قرآن حکیم بار بار نظر و انتہار کی دعوت دیتا
ہے.غرضیکہ صوفی ازم پر یقین نہیں رکھتا تھا.جہاں تک اشاعرہ کا تعلق ہے ( امام الغزالی" کا تعلق اس گروہ سے تھا ) نے ان کو دل کھول کر ہدف
تنقید بنایا ہے.کے نزدیک عقائد کے جو دلائل قرآن میں موجود ہیں وہ اہل بربان اور عوام دونوں کے لئے
تسلی بخش ہیں کیونکہ ایک طرف تو وہ یقینی ہیں اور دوسر کی طرف سادہ، غیر مرکب ہیں.لیکن اشاعرہ کے دلائل ان
دونوں اوصاف سے عاری ہیں، نہ تو وہ نظری طور پر یعنی ہیں اور نہ شرعی دلائل کی طرح وہ سادہ اور قطعی ہیں.اس طور
پر اس نے سب سے پہلے ان دلائل پر سیر حاصل بحث کی ہے جو اشاعرہ اور قرآن حکیم نے خدا تعالی کے وجود پر قائم
کئے ہیں.قرآن حکیم میں اللہ تعالی نے اپنے وجود پر دو قسم کے دلائل پیش کئے ہیں ، ان کو نے دلیل عنایہ اور
دلیل اختراع میں تقسیم کیا ہے:
(1) دلیل عنایہ کی بنیاد دو باتوں پر ہے ایک تو یہ کہ دنیا کی تمام چیزیں انسانی ضروریات اور انسانی فوائد کی
خاطر بنائی گئی ہیں مثلاً چاند، سورج، دن، رات ، سردی، گرمی، نباتات، جمادات ، بیل بوٹوں پر غور کرنے سے معلوم
ہوتا ہے کہ وہ انسان کے لئے کس قدر مفید اور اس کی ضروریات کے لئے کس قدر موزوں ہیں.اس لئے جو شخص خدا
کے وجود کا پتہ لگانا چاہتا ہے اس کے لئے موجودات کے فوائد پر تحقیق لازمی ہے.دوسرے یہ کہ اس کائنات کے تمام
اجزاء، انسانی وجود اور موجودات کے نہایت موافق ہیں.مثلاً اگر ایک شخص زمین پر ایک پتھر کو دیکھے جو اس طرح
تراشا گیا ہے کہ اس پر آرام سے بیچا جا سکتا ہے.لیکن اگر یہ پتھر اس طرح پڑا ہوا ہے کہ یہ بیٹھنے کے لائق نہیں ہے تو
انسان یقین کر لیتا ہے کہ پتھر اتفاق سے زمین پر آن گرا ہے.کسی نے اس کو خاص مقصد کی خاطر نہیں رکھا ہے.اس
طرح انسان جب کائنات کے اجزاء کو دیکھتا ہے کہ کس طرح وہ انسان کے فوائد کے عین مطابق ہیں تو یقین ہو جاتا
Page 78
ہے کہ دنیا کو ضرور کوئی پیدا کرنے والا ہے.اس لئے یہ دلیل خدا کے وجود پر بہترین دلیل ہے اور اسی کا قرآن حکیم
نے بار بار اعادہ کیا ہے.(امریکہ میں آجکل اس نظریہ کا بہت چرچا ہے یہاں اسے انٹیلی جنیٹ ڈیزائن
(intelligent design ) تھیوری کا نام دیا جاتا ہے مثلاً پرندوں ، جانوروں اور انسان میں آنکھ کا ڈیزائن کہنا
پیچیدہ اور محمدہ ہے.)
(2) دلیل اختراع کی بنیاد بھی دو اصولوں پر ہے، ایک یہ کہ تمام کائنات مخلوق ہے اور دوسرے یہ کہ جو چیز
مخلوق ہے اس کا ضرور کوئی خالق ہے، لہذا جو ہر اشیاء کا علم لازمی ہے کیونکہ جس کسی شخص کو کسی چیز کی حقیقت معلوم
نہیں ہوگی اس کو صانع حقیقی کا علم نہیں ہوگا.اشاعرہ نے لیکن خدا کے، جود پر جو دلیل قائم کی ہے اس کے مطابق خدا کے وجود پر موجودات کی دلالت کسی
حکمت کی بناء پر نہیں ہے بلکہ اس کی بنیاد جواز پر ہے.یعنی دنیا کا جو نظام قائم ہے اس کے برعکس بھی نظام قائم ہو سکتا
تھا.انسان کے اعضاء کی جو شکل اور تعداد ہے اس کے خلاف بھی شکل اور تعداد ہوسکتی تھی.لیکن کے نزدیک
دنیا کا جو نظام قائم ہے وہ ضروری ہے اور اس سے بہتر اور اس سے مکمل نظام قائم نہیں ہو سکتا ہے.مثلاً انسان کے
ہاتھ کی شکل اور انگلیوں کی تعداد اگر پکڑنے کے لحاظ سے افضل نہ ہو بلکہ جانوروں کی طرح اس کے گھر ہوں تو جو لوگ
خدا کے وجود کے منکر ہیں اور اتفاق کے قائل ہیں ان کے خلاف کونسی دلیل قائم کی جاسکتی ہے؟
کچھ بھی ہو دنیا کی چیزوں میں جو حکمتیں پائی جاتی ہیں انہی سے خدا کے وجود پر استدلال کیا جا سکتا ہے.بظاہر جس چیز کی کوئی مثال موجود نہیں ہوتی اس کو عوام بہ آسانی سمجھ نہیں سکتے اس لئے خدا تعالیٰ نے اس کو مثالوں
تلك الامثال نضربها للناس ) سے سمجھایا ہے.جیسے خدا نے دنیا کو ایک زمان میں اور ایک چیز سے پیدا کیا
ہے.تخلیق عالم سے پہلے خدا کا تخت پانی پر تھا.خدا نے آسمانوں اور زمین کو چھ دنوں میں پیدا کیا.قرآن پاک کی
اس
قسم کی آیات کی تادیل عوام کے لئے نہیں کرنی چاہئے کیونکہ وہ ان کا ہم نہیں رکھتے.تاویل صرف تین مواقع پر
ہو سکتی ہے ( اول ) جہاں قرآن کی آیات کی تاویل میں اجتماع ممکن نہ ہو ( دوم ) جہاں آیات کریمہ ایک دوسرے
سے بظاہر متضاد ہوں ( سوم ) جہاں قرآن کی آیات فلسفہ اور نیچرل سائنس سے میل نہ کھاتی ہوں.كشف المناهيج کا انگریزی میں ترجمہ ابراہیم نجار نے Faith and Reason in Islam کے
عنوان سے کیا ہے اور یہ آکسفورڈ سے 2001ء میں شائع ہوا ہے.60
Page 79
باب سوئم بحیثیت طبیب
جیسا کہ اس کتاب کے شروع میں ذکر کیا گیا نے طب کی تعلیم ابو جعفر ہارون اتر جالی جیسے مشہور اور
بے مثل استاد سے حاصل کی تھی جو اشبیلیہ میں طبابت اور تدریس سے وابستہ تھا.یعنی دن کے اوقات میں وہ مطب
کرتا تھا اور سہ پہر کے بعد طلبہ کو طب کی تعلیم دیتا تھا.اس وقت کے نامور طبیب ابن طفیل سے بھی کی دوستی
تھی اس لئے طب میں مہارت حاصل کر لینا عین فطری معلوم ہوتا ہے.یہ بات مسلمہ ہے کہ طب پر ماہرانہ
قدرت اور کما حقہ گرفت رکھتا تھا.نے جب مطب کا سلسلہ شروع کیا تو جلد ہی اس کو اپنی پریکٹس کے ذریعے اتنا تجربہ حاصل ہو گیا کہ
زندگی کے چھتیسویں زینے پر جب قدم رکھا تو 1162 ء میں کتاب الکلیات قلم بند کی.کتاب کب لکھنی شروع کی
اس کے بارے میں معلوم نہیں ، ہاں قرین قیاس ہے کہ کم از کم چار سال تو ضر در قلم بند کرنے میں صرف ہوئے
ہوں گے.کسی طبیب کا مطلب کے ساتھ تصنیف و تالیف کا کام کرنا بڑا معنی رکھتا ہے.نبض اور پیشاب دیکھ
کر تشخیص کرتا تھا.ایسا لگتا ہے کہ جو مریض اس کے پاس علاج کے لئے آتے ہوں گے ان میں سے ہر ایک کی فائل
اس نے تیار کی ہوگی اور مریض کی بیماری کی مدت، علاج، تشخیص ، دواؤں کی تفصیل درج کی ہوگی.کیونکہ انہی
تحریروں ( اور درجنوں مریضوں کی علامات مرض) کی بناء پر طبیب مرض کی شناخت کے ساتھ ساتھ کتاب کے لئے
مواد تیار کر لیتا تھا.طبیبوں کو امراض کی پیش بینی (Prognosis) کا علم بھی اسی طرح ہوتا ہے مثلاً زکام کے
چار مریضوں میں مرض ٹھیک ہونے میں کتنا وقت لگا؟ اگر ان میں سے ہر ایک کو تین ہفتے لگے تو یقیناً پانچویں مریض کو
بتانا آسان ہوگا کہ تمہیں ٹھیک ہونے میں تین ہفتے لگیں گے.طب میں اس کی عالمگیر شہرت
دو یادگار دریافتوں کی میجہ سے ہے.پہلی عظیم الشان دریافت یہ تھی کہ جس
مریض کو چیچک (Small Pox) ایک بار ہو جائے پھر اسے دوبارہ لاحق نہیں ہوتی.اغلب ہے کہ اس دریافت کا
61
}
'
:
Page 80
پتہ اس نے مطب کے دوران سیکڑوں مریضوں کے مینی مشاہدات سے لگایا ہوگا بہر حال مسمی طریقہ دریافت پر اس
کی سوانحی کتابیں خاموش ہیں.دوسری دریافت یہ تھی کہ آنکھ کا پردہ بصارت (Retina) نہ کہ عدسہ (Lens) آنکھ
میں فوٹو رسیپٹر (Photo Receptor) کا کام کرتا ہے.یہ دریافت بھی کوئی آسان دریافت نہیں تھی کیونکہ ابن
رشد سے قبل تمام بڑے بڑے ماہرین امراض چشم (جیسے حسین ابن الطق) خیال کرتے تھے کہ اشیا کے دیکھنے میں آنکھ
کا عدسہ بنیادی حیثیت رکھتا ہے، مگر نے کہا کہ عدسہ نہیں بلکہ بینائی کی جس پر وہ بھارت میں ہوتی ہے
sense of sight originates in the retina) - پردہ بصارت ( ریٹینا ) کی وضاحت یوں کی جاسکتی
ہے کہ جس طرح کیمرے کے اندر فلم ہوتی ہے اس طرح ہماری آنکھ میں رینینا ہوتا ہے.اگر فلم کے بغیر کیمرہ بے کار
ہے تو ریٹینا کے بغیر آنکھ بے کار ہے.ریٹینا آنے والی شعاعوں کو الیکٹریکل سگنلز میں تبدیل کر کے عصب باصرہ یعنی
آپنک نرو (Optic Nerve) کے ذریعے دماغ کی طرف بھیجتا ہے جس طرح ظلم ڈیولپ کی جاتی ہے.ریٹینا کی
وجہ سے ہم رنگین چیز وں کو دیکھ سکتے ہیں، اور اس کی بدولت ہمیں پیری فرل ویژن (Peripheral Vision)
حاصل ہوتا ہے.جب یہ ناقص ہو جاتا ہے تو انسان بینائی سے محروم ہو جاتا ہے.جارج سارٹن کا کہنا ہے کہ "الکلیات میں کئی بیش قیمت مشاہدات پائے جاتے ہیں مثلاً پہلا مشخص
تھا جس نے پردہ بصارت کا صحیح مصرف معلوم کیا ( اس سے پہلے ماہرین چشم خیال کرتے تھے کہ بصارت آنکھ کے
عد سے میں ہوتی ہے.) اس نے یہ بھی مشاہدہ کیا کہ جس شخص کو ایک بار چیچک ہو جائے پھر اسے زندگی بھر کے لئے
چیچک سے چھٹکارا مل جاتا ہے.بلاشبہ وہ مسلمہ طبیب ، بلکہ اپنے زمانے میں کرہ ارض کا عالی طبع طبیب تھا.اصل
حوالہ درج ذیل ہے:
"Kulliyat contained other valuable observations; for example, Ibn Rushd
seems to have been the first to understand the function of retina (earliest
oculists thought that visual perception occurred in the lens); and he
realized that an attack of smallpox confers immunity.He was
unquestionably a great physician, one of the greatest of his time
anywhere." (17)
ایک مغربی مصنف را جر آرنلڈس (Arnaldez) کا کہتا ہے کہ اس بات کی تصدیق نہیں ہو سکی کہ آیا خلیفہ ابو یعقوب یوسف کا شاہی طبیب مقرر ہونے سے قبل مطلب
کرتا تھا یا نہیں اور نہ ہی یہ معلوم ہوسکا ہے کہ وہ خلیفہ
کا کس قسم کا علاج کرتا تھا یا پھر اس کا کام طبی مشورے کی حد تک تھا.فاضل مصنف کا کہنا ہے کہ کا طلب کا علم
62
Page 81
سراسر کتابی تھا، لیکن یہ کتابی یا نظری مطالعہ بہت وقیع تھا اسی لئے تو اس نے طلب پر میں کتابیں
لکھیں.نیز طب کا علم
اس وقت بھی اس کے کام آیا جب اس نے ارسطو کی نیچرل ہسٹری کی کتابوں جیسے کتاب الحیوان کی شرح لکھی.جالینوس کی کتابوں اور طبی نظریات کے بارے میں بھی اس کا علم بہت وسیع تھا.(18) کہتا تھا کہ اچھی صحت برقرار رکھنے کے لئے اچھا باضمہ اور ہر روز اجابت با فراغت ضروری ہے.مسلمان اطباء کا کام اپنے مریضوں کے علاج کے ساتھ ساتھ ان کی صحت کو برقرار رکھنے کی کوششوں سے بھی تھا.غذا
جو انسان کھاتا ہے اس کو بڑی اہمیت دی جاتی تھی.اگر نا مناسب غذا کھانے سے بیماری لاحق ہو جاتی تو طبیب ایسی
غذا تجویز کرتے جس سے برے اثرات کم ہو جاتے.غذا اور صحت کے موضوع پر کے دوست ابو مروان ابن
زہر کی تصنیف کتاب الاغذیہ بہت اہمیت رکھتی ہے.ابن زہر کا کہنا تھا کہ سردیوں میں زیادہ کھانا چاہئے بنسبت
گرمیوں کے کیونکہ سردیوں میں نظام ہضم زیادہ تیز ہوتا ہے.موسم سرما میں ایسی خشک غذا ئیں تناول کریں جن کی
تاثیر گرم ہو.ان تمام باتوں سے آگاہ تھا.اس نے کتاب الکلیات میں تاکید کی ہے کہ امراض کے علاج
کے لئے ابن زہر کی کتاب کا مطالعہ از حد بنیادی ہے (17) - کلیات لکھنے کی غرض وغایت اس نے یوں بیان کی ہے.میں نے اس تصنیف میں فن طب کے امور کلیہ کو جمع کر دیا ہے اور ایک ایک عضو کے امراض کو الگ الگ
بیان نہیں کیا ہے کیونکہ اس کی کچھ ضرورت بھی نہیں ہے.یہ باتیں امور کلیہ سے مستنبط ہوتی ہیں.لیکن جب کبھی
مجھے ضروری امور سے فرصت ہوئی تو میں اس موضوع پر کچھ لکھنے کی کوشش کروں گا.فی الحال ابو مروان ابن زہر کی
کتاب التیسیر اس کے لئے کافی ہے جو میری فرمائش پر اس نے قلم بند کی ہے."
امور کلیه یعنی کلیات فی الطب سے مراد طب کے عام اصول و قواعد ( general Principles
of Medicine) ہیں.اس کے برعکس جزئیات فی الطب (پارتیکولرز آف میڈلین (Particulars of
Medicine ) سر سے پاؤں تک کے امراض کا بیان ہے.چنانچہ نے کلیات پر کتاب لکھی اور اس کے
دوست ابن زہر نے اس کی فرمائش پر جزئیات پر کتاب لکھی تا کہ صنعت طب پر یہ دونوں کتابیں مستند مجموعہ بن
جائیں.جزئیات میں سر سے پاؤں تک کے تمام اعضاء کا مشاہدہ کیا جاتا ہے اور ہر عضو کو لاحق ہونے والی بیماری کا
ذکر کیا جاتا ہے پھر ان کا علاج کلیات میں تلاش کیا جاتا ہے.کتاب الکلیات میں جالینوس کے طریق علاج پر کافی
انحصار کیا گیا ہے البتہ بقراط کا ذکر بھی کہیں کہیں کیا ہے.اس کتاب میں نے ابن زہر کو جالینوس کے بعد دنیا
کا سب سے عظیم طبیب قرار دیا تھا.کتاب الكليات سات حصوں میں تقسیم ہے.تشریح الاعضاء (Anatomy of Organs).63
Page 82
الصحة ( Health ) المرض (Diseases) الادويه والاغذيه Drugs Foods) حفظ الصحة
(Hygiene) شفاء المرض (Therapy) اور العلامات (Symptoms of Disease) - کتاب
کے بعض اصل اجزاء عربی میں اور لاطینی میں اسکو ریال لائبریری میں موجود ہیں.اس کی زبر دست افادیت کے پیش
نظر ائی کے یہودی اسکالر بینا کو سا (Banacosa) نے پیڈ ڈا میں اس کا لاطینی میں ترجمہ کا لجھیٹ
(Colliget) کے عنوان سے 1255 ء میں کیا تھا.اس کا عبرانی ترجمہ ابراهام بن ڈیوڈ ( Abraham ben
David) نے کیا تھا جبکہ عبرانی نظم میں اس کو موسمز این طبون (1260 Moses ben Tibbon ) نے
ڈھالا.عبرانی میں ایک اور ترجمہ فرانس کے شہر بے زئیرز (Beziers) میں 1261 ء میں غرناطہ کے سالومن بن
جوزف ( Solomon ben Josephs) نے کیا.اور اس کا ایک لاطینی ترجمه مشهور مترجم آرمن گاڈ بین بلیس
(Armengaud ben Blaisc) نے میں سال بعد 1284ء میں کیا جو دنیس (اٹلی) سے 1496 ء میں طبع
ہوا.عربی متن بمع لاطینی ترجمہ آکسفورڈ سے 1778ء میں اور فرانسیسی ترجمہ 1861ء میں شائع ہوا.یورپ کے
میڈیکل اسکولز کی ریڈنگ لسٹ میں یہ کتاب انیسویں صدی تک شامل تھی.یو نیورسٹی آف پیڈوا (اٹلی) میں
القانون في الطب اور کتاب الکلیات دونوں طب کی درسی کتابوں کے طور پر پڑھائی جاتی تھیں.کتاب الکلیات کا پہلا پرنٹ ایڈیشن 1482ء میں دنیس کے مطبع سے شائع ہوا تھا.کتاب الکلیات
اکثر ایک جلد میں زکریا رازی اور یخنی ابن سرافیون کی کتابوں کے ہمراہ شائع ہوا کرتی تھی مثلاً اسٹراس بورگ
کا 1531 ء کا ایڈیشن.اس کے علاوہ ابن زہر کی کتاب النیسیر کے ہمراہ ایک جلد میں و فیس شہر سے یہ سات بار
(1490.1496,1497,1514,1530,1531,1533ء) شائع ہوئی تھی.کینیڈا کے شہرہ آفاق تعلیمی ادارے یونیورسٹی آف میک گل ( مانٹریال) کی لائبریری میں کتاب الکلیات
کا وہ لاطینی ایڈیشن موجود ہے جو 1482ء میں شائع ہوا تھا.اس کے 116 صفحات ہیں.جلد چمڑے کی ہے.اسی
طرح ایک اور لاطینی ایڈیشن بھی موجود ہے جو 1562ء میں وفیس سے شائع ہوا تھا.ٹائٹل پیج پر لکھا ہے:
لکھا
cantica item Avicennae cum eiusdem Averrois commentariis
اس کے علاوہ ٹائٹل پیچ جرمن میں بھی ہے : Die Medizinischen Kompendium.اس کے
312 صفحات ہیں.مزید معلومات کے لئے لائبریری کی ویب سائٹ دیکھی جاسکتی ہے.http://aleph.mcgill.ca
الكليات في الطب بمع حاشیہ جے ایم فور نیاس (J.M.Fomeas) نے میڈرڈ سے دو جلدوں میں
1987 ء میں شائع کی تھی.اس کا اصل عربی متن اور اردو ترجمہ دو الگ الگ جلدوں میں یونانی طب کی مرکزی کونسل نئی
64
Page 83
دیلی سے علی الترتیب 1980ء اور 1984ء میں شائع ہوئے ہیں.اردو ترجمہ دوسری بار 1987ء میں بھی چھپا ہے.مغرب میں کی شہرت فلسفہ اور ارسطو کی کتابوں کی تفاسیر کی وجہ سے ہے.جبکہ مشرق میں اس کی شہرت
بے نظیر فقیہ اور عالی مرتبہ طبیب کی بناء پر ہے.کتاب الکلیات ابن سینا کی القانون فی الطب کی پہلی جلد سے
بہت مطابقت رکھتی ہے.ابن سینا نے نظریاتی طلب کی مختلف شاخوں کے تذکرے کے بعد کہا ہے کہ جو شخص ان پر مکمل
عبور حاصل کرلے وہ خود کو طبیب کہہ سکتا ہے چاہے دوبا قاعدہ مطلب نہ بھی کرتا ہو.اس نقطہ نظر سے کو اتفاق
ہے.اس لئے کہ ابن سینا کی اس سند سے خود کو طبیب کہلانے کا حق دار سمجھتا تھا.کتاب الکلیات میں اس
نے سائیکالوجی پر جن نظریات کا اظہار کیا، ان نظریات سے امریکی مصنف ولیم جیمز ( William James
1842-1910ء) نے اپنی کتاب پرنسپلز آف سائیکالوجی (Principles of Psychology) میں خوب
استفادہ کیا ہے (19).پروفیسر نیوئے برگر اس کتاب کے بارے میں لکھتا ہے:
"Colliget betrays extraordinary wide reading, a gift for adaptation and a
mastery of dialectics.It is a colossal commentary upon the first book of
Canon.It presents little that is new; the practical contents may be looked
upon as the ripe fruit of author's reading"(20)
کلیات سمیت فن طب پر کی 20 کتابوں کی تفصیل درج ذیل ہے: جالینوس کی طب پر 8 کتابوں کی
تلاخيص تلخيص كتاب التعرف ، تلخيص كتاب القوى الطبيعية ، تلخيص كتاب العلل
والاعراض، تلخیص کتاب الاسطقسات ، تلخيص كتاب حيلة البر، تلخيص كتاب المزاج ،
تلخيص كتاب الحميات، تلخيص كتاب الادوية المفردہ ہیں.ان کتابوں کے عربی مخطوطات ابھی
تک موجود ہیں.مقاله فی التریاق کا ترجمہ اینڈریا الیا گوAndrea Alpag) نے لاطینی میں کیا.اس کا
مخطوطہ اسکور یال (اپین) کی لائبریری میں ہے.کلام علی مسئلة من العلل عبرانی زبان میں اس کا ترجمہ
لیڈن، ہالینڈ میں موجود ہے.مقاله في المزاج ، مـ
، مقاله فى حيلة البر، مقاله في المزاج المعتدل ،
مقاله في نوائب الحمى، مقاله في حميات العفن.دو کتا ہیں جن کے لاطینی عنوان یہ ہیں:
De spermalo اور Canonis de medicinis Laxatives - مراجعات و مباحث بین آبی
بكر ابن الطفيل و بين فی رسمه للدواء فى كتابه الموسوم بالكليات
65
Page 84
شرح ارجوزه في الطب
شیخ الرئیس ابن سینا کی طب پر منظوم کتاب الارجوزه في الطب ( يا شرح منظومه في الطب ) جو عربي
میں 1326 اشعار پر مشتمل ہے، نے اس کی شرح لکھی تھی.عبرانی میں اس کا ترجمہ موسیٰ ابن میمون نے
1260ء میں کیا.عبرانی نظم میں فرانس کے شہر بے زمیئر (Beziers) سے اس کو غرناطہ کے ایوب ابن جوزف نے
1261ء میں منتقل کیا.لاطینی میں اس کا ترجمہ آرمن گاڈ (Armenguad) نے کمیٹی کم ڈی میڈی سینا
( Canticum de Medicina) کے عنوان سے کیا جو وفیس (Venice) سے 1484ء میں زیور طبع سے
آراستہ ہوا.اس کا قلمی نسخہ امریکہ کی ایک لائبریری میں موجود ہے:
(Yale University Library, Landberg Collection, MS 157 # 151
الألــ
ایک نسخہ نیشنل لائبریری آف میڈیسن (میری لینڈ ، امریکہ ) میں بھی موجود ہے جس کا عنوان شرح علی
ــفيـ ہے.اصل نظم سرخ رنگ کی روشنائی میں جبکہ شرح سیاہ رنگ کی روشنائی میں لکھی گئی ہے.www.nlm.nih.gov/hmd/arabic/poetry_3.html - ہندوستان میں کی شرح ارجوزہ
1829ء میں کلکتہ سے اور 1845101261ء میں لکھنو سے شائع ہوئی ہے.ابن سینا اکاڈمی علی گڑھ کی ظل الرحمن
لائبریری میں کلکتہ کی اشاعت محفوظ ہے.حکمت و معرفت سے بھر پور اس طویل نظم کے چند اشعار یہاں پیش کئے
جاتے ہیں:
تدبير النوم
853 لا تطل النوم فتؤدى النفسا ولا تور قها فتوذى الحسا
854 وطول التوم لغير المتهضم من الطعام او على أثر التخم
855 ولا تطل نوماً بوقت الجوع تبخر الراس من الرجيع
856 نم با ستسناد اثر الطعام حتى يحل موضع انهضام
ذكر اصناف الادوية
997 و ها انا اذكر من عقار ما يخرج الاخلاط بالاحدار
998 و ما تراه غالب المزاج وما له في الخلط من اخراج "
999 و ما به تفتح اوتلین
ما
و به تحرق او تعفن
1000 و ما به تنضج او تصلب وما يسد فتحاً او ما يجذب
66
Page 85
1001ونا تجلو به و ما تخلخل و تثبت اللحم به او تحمل
1002 و شبه ذاك من قوى ثوان و من ثوالث بلا توان
ذكرى قوى الادوية
و مثلها
1033 و للعقاقير قوی اوائل
ثانیه عوامل
1034 و للعقاقير قوی ثوالث تصدر عنها ان بدت حوادث
1035 فالقوه الأولى هي اسلخونة والبرد واليبس مع الدونة
1036 وها انا مبتدی و مورد من
العقاقير بما يبرد
[Taken from the book "Medicine Arabes Anciens" by Jean-Charles
Sournia.Conseil International de la Langue Francaise - Paris 1986
محولہ بالا کتاب میں الارجوز فی الطب کے اشعار عربی زبان میں اور ان کا ترجمہ مقابل صفحے پر
فرانسیسی میں دیا گیا ہے.ایک مصنف ڈیوڈ ریس مین کے مطابق کا کہنا ہے کہ جس طرح ہم قدرتی آفات کے طبعی اسباب
کی تلاش مظاہر قدرت میں کرتے ہیں اسی طرح ہمیں جسمانی اور وبائی امراض کے طبعی اسباب فطرت میں تلاش
کرنے چاہئے:
"He held that direct physical causes of disease and epidemics must
be sought just like those of other natural phenomenon."(21) کے مقولے اس کے افعال و خصائل کی طرح حکیمانہ رنگ میں ڈوبے ہوتے تھے.چنانچہ اناٹومی
( علم الاعضاء ) سے متعلق اس کا درج ذیل مقوله بہت مشہور بولا: من اشتغل بعلم التشريح ازداد ايمانا بالله
علم تشریح کی واقفیت سے اللہ پر انسان کا ایمان تازہ اور تو کی ہو جاتا ہے.اور جالینوس
جالینوس (Galen 130-200 AD) عہد قدیم کا سب سے عظیم طبیب اور فلسفی تھا.اس نے طب میں دو
سو سے زیادہ قابل ذکر کتابیں قلم بند کیں، جن میں سے 140 یونانی زبان میں محفوظ ہیں.یونانی میں اگر چہ اس کی
کتابیں امتداد زمانہ کے ہاتھوں خرد برد ہو گئیں مگر ان کے تراجم عربی اور لاطینی میں دستیاب ہیں.اس کی زیادہ تر
67
Page 86
تصنیفات طب پر ہیں.مسلمانوں نے علم طب انہی کتابوں سے اخذ کیا.اس کے حکیمانہ مقولے دنیا بھر میں زبان زد
عام ہیں.جالینوس کہتا تھا کہ ہر طبیب کے لئے فلسفی ہونا ضروری ہے اور فلسفی وہ شخص ہے جو سچائی سے پیار کرتا ہے.این رشد نے اس کی کتابوں کے خلاصے تیار کئے جیسے مقالہ فی اصناف المزاج ونقد مذهب جالينوس
مقالة في حيلة البر - تلخيص كتاب المزاج لجالينوس - جب جالینوس کا ذکر کرتا ہے تو
کہتا ہے قال جالینوس اور پھر جب اس پر تبصرہ کرتا ہے تو کہتا ہے قلت.نے جالینوس کے ان
نظریات پر کڑی تنقید کی جوارسطو کے نظریات سے مطابقت نہیں رکھتے تھے.مثلاً " جالینوس کا دو حوالہ جس میں ودان
یونانی طبیبوں اور فلسفیوں کا ذکر کرتا ہے جو کہتے ہیں کہ تمام نوع انسانی نے ایک عصر سے نمود پایا ہے کیونکہ چاروں
عناصر ایک دوسرے میں منتقل ہو جاتے ہیں".بنی نوع انسان کی نمود کے اس نظریے پر جالینوس اور بقراط نے تنقید
کی تھی.یہ دونوں طبیب ارسطو سے اتفاق کرتے تھے کہ کسی چیز کے بننے میں یہ چاروں عناصر شامل ہوتے ہیں بشمول
انسان کے جسم کے.ارسطو نے یہ بھی کہا کہ چاروں عناصر ایک دوسرے میں تبدیل نہیں ہوتے ہیں.چونکہ یہ دونوں
طبیب ارسطو کے نظریات سے اتفاق کرتے تھے اس لئے بھی ان سے اتفاق کرتا تھا.جالینوس کی کتاب آرٹ آف ہیلنگ ( حيلة البسر) میں مذکور ہے کہ جہاں تک معالجے کا تعلق ہے عموماً
طبیب علاج کے وقت یہ مقولہ مد نظر رکھتے ہیں:
Opposite heals its opposite and the like heals its like.فلاسفہ کا اس کے برعکس کہنا ہے کہ:
"Healing consists in the progress from one given principle to another
in accordance with a fixed procedure directed towards a desired result." کہتا تھا کہ نہ صرف معالجہ بلکہ تمام طبی تدابیر میں طبی و فطری طریقے کو مد نظر رکھنا چاہئے کیونکہ فطرت
کے شفا کے طریقے انسانی طریقوں سے حد درجہ فائق ہیں.چنانچہ صحت کی بحالی کے لئے شفا کے فطری طریقوں
سے فائدہ اٹھانا چاہئے.جسمانی ورزش اکسل ، مالش جیسے اعمال سرجری اور دواؤں سے زیادہ موثر ہوتے ہیں.جب کوئی طبیب مریض کا علاج کرتا ہے تو وہ فطرت کے اصولوں کی پابندی کرتے ہوئے ایک خاص مقصد کی طرف
رہنمائی کر رہا ہوتا ہے ، یہ مقصد یا تو مرض کا خاتمہ یا پھر صحت کی بحالی ہوتا ہے.ارسطو کی کتاب پاروانا طور الیا
(Parva Naturalia) سے حوالہ دیتا ہے کہ اکثر مریض جو موت کا نشانہ بن جاتے ہیں وہ غلط دوا کی وجہ سے نہیں
بلکہ طبیب کی غلطی سے بنتے ہیں.ارسطو کا مطلب اس حکمت کی بات میں کچھ بھی مخفی ہو اس سے اتفاق کرتا
68
Page 87
ہے کہ طب کی نظری اور عملی تعلیم کے لئے منطق اور طبیعیات
کا علم لازمی شرط ہے.یورپ میں کی شہرت اور قدر کی اصل وجہ یہ تھی کہ یورپ کے عالم نئے نئے فلسفے سے آشنا ہوئے
تھے.فلسفے کا مطالعہ ارسطو کے مطالعے کے بغیر ناممکن تھا اور ارسطو کا مستند شارح تھا.اس لئے وہاں کی شہرت اس کی طبعی اور فلسفیانہ کتابوں کی بدولت ہوئی.طب میں جو شہرت ابن سینا کی القانون کو یورپ میں
حاصل ہوئی وہ کی الکلیات کو نصیب نہ ہو سکی.طب میں جالینوس کا پیرو کار تھا لیکن جہاں جالینوس
نے ارسطو سے مختلف نقطہ نظر بیان کیا ، وہاں نے ارسطو کے نظریے سے اتفاق کیا جیسے ارسطو اور جالینوس میں
ایک نزاعی مسئلہ یہ تھا کہ دماغ اور دل میں سے کسی عضو کورئیس الاعضاء کی حیثیت حاصل ہے؟ ارسطو کے خیال میں یہ
دل تھا مگر جالینوس کے مطابق یہ دماغ تھا.نے اس مسئلے میں ارسطو سے اتفاق کیا.اور علم الادویہ
کتاب الکلیات کے پانچویں باب الادويه والاغذيه " میں نے القول فی قوانین
التركيب (Rules of Composition) کے عنوان سے ادویہ کی ترکیب د تیاری کے بارے میں اظہار خیال
کیا ہے.اس باب کے مطالعے سے علم الادویہ میں اس کی گہری معلومات اور وسعت کا اندازہ ہوتا ہے.نے لکھا ہے کہ طبیب دوا دیتے وقت مفرد دوا کے بجائے مرکب دواد ینے پر کیوں مجبور ہو جاتا ہے؟ اس کی اس نے
تین جہیں بیان کی ہیں: مفرد و وا مطلوبہ خواص میں دستیاب نہیں.مفرد دوا میں مطلوبہ خواص تو ہیں مگر مطلوبہ مقدار
میں نہیں.مفرد دوا میں کوئی ایسی خاصیت ہے جو مریض کے لئے مضر ہے.مثال دیتا ہے کہ اگر جلاب آور دوا تیار کرنی ہو اور اس کے لئے چار قسم کی مفرد دوائیں درکار ہوں تو
طبیب ہر دوا کا چوتھائی حصہ لے کر مشروب تیار کرے.غرض یہ وہ جامع دستور اور قوانین ہیں جن کا استعمال کمیت
کے لئے کیا جاتا ہے.اس کا کہنا تھا کہ انسانی جسم کے دوا سے رد عمل کو قبل از وقت دوا کے جزئیات کا تجزیہ کر کے (جن سے مرکب
دوا بنتی ہے ) بیان نہیں کیا جاسکتا."The actions of drugs upon bodies are only a relative matter.In truth, this
is not something that is consequent upon the parts of the drug itself.It
may happen that a drug that is itself less hot will be, relative to the human
69
Page 88
body, hotter than a drug that itself possesses greater heat."
اس موضوع سے دلچسپی رکھنے والے قارئین درج ذیل مضمون کا مطالعہ فرمائیں:
Ibn Rushd's critique of Al-Kindi - Pharmacological Computus - Enterprise
of Science in Islam by A.1.Sabra (22) اور علم بصریات
جیسا کہ اس باب کے شروع میں ذکر کیا گیا کہ دنیا کا پہلا طبیب تھا جس نے کہا کہ آنکھ کا پردہ
بصارت آنکھ میں فوٹوری سیپٹر کا کام کرتا ہے.حسن اتفاق سے مجھے کوئیز یونیورسٹی کی میڈکل لائبریری میں جرنل آف
دی ہسٹری آف میڈیسن نمبر 24، 1969ء کے جنوری کے شمارے میں وہ مضمون مل گیا جس کا عنوان ہے " کا نقطہ نظر پردہ بصارت کے متعلق (Averroes View of the Retina ).مصنف نے یہ مضمون کتاب
الکلیات کے چار لاطینی تراجم سے تیار کیا جو دنیس (اٹلی) 1574 156 155 1514ء میں شائع
ہوئے تھے.مصنف کہتا ہے کہ پہلا سائنس داں تھا جس نے کہا کہ پردہ بصارت آنکھ میں فونوری سپیٹر
کا کام کرتا ہے جبکہ یہ دریافت یورپ میں پلاٹر (Platter) نے پانچ سو سال بعد کی کیپلر (Kepler) نے بھی اس
سے مکمل اتفاق کیا.حیرانی کی بات یہ ہے کہ کتاب الکلیات کا لاطینی ترجمہ 1255ء میں کیا گیا مگر کسی نے اس
معرکتہ الآراء دریافت کی طرف توجہ نہ کی.بیسویں صدی میں اس دریافت کا ذکر ایک مصنف فوکالا
(Fukala) نے فرسٹ ہینڈ آبزرویشن کے بعد ایک مضمون میں کیا.نے کتاب الکلیات میں جالینوس کے اس نقطہ نظر کی تردید کی کہ آنکھ کا عد سہ روشنی ملنے پر رد عمل
کرتا ہے.اس نے کہا کہ عدس عکس (image ) بناتا ہے جو پردہ بصارت کو بھیج دیا جاتا ہے وہ در حقیقت روشنی ملنے پر
رد عمل کرتا ہے (sensitive to light) کتاب الکلیات کے ابواب 2:15 اور 3:38 میں نے
آنکھ پر مفصل روشنی ڈالی.باب 2:15 کا اقتباس درج ذیل ہے:
"It seems that the proper instrument of the visual sense should be either
the round humor, called glacial, or the zonule (lens) located anterior to
this humor...The tunic called the chorioid was created for the nutrition of
the retina through its veins; and that it may nourish itself becaue of the
natural heat passing through its own arteries.Nutrition of the retina is
70
Page 89
first in order that it may pass the visual spirit through the nerves inside the
retina; this nutrition is the natural heat, the complexion of which has been
adjusted in the brain, and it comes through the two nerves proceeding to
the eyes.The retina nourishes the lens by way of drops of moisture and
gives the nourishment of natural heat via its arteries.But Ali ibn Isa
avows that the zonule is of ultimate perviousness and lucidity, because
colors and forms are imprinted in it.Therefore the same tunic (the zonule)
is the actual instrument of sight, either by itself or with the assistance of
But the eye receives colors through its transparent parts after
the lens
the manner of a mirror, and when colors are impressed upon it, the visual
spirit apprehends them." (Colliget, II, 15)...یہاں نے کہا ہے کہ رنگ اور تصویر بعد سر اسی طرح اکٹھا کرتا ہے جس طرح آئینہ کرتا ہے.تصویر یہاں سے
پردہ کبصارت اور عصب بصری ( آپنک نزد) سے ہوتے ہوئے دماغ تک پہنچتی ہے.نے پردہ بصارت کو
نیٹ ورک آف بلڈ سیلز (network of blood vessels) کہا ہے (23).طب میں علمی کارنامے
طب میں کے علمی کارنامے مختصر یہ ہیں:
طویل مشاہدات کے بعد انکشاف کیا کہ جس شخص کو چک ایک بار ہو جائے یہ اسے دوبارہ لاحق نہیں ہوتی.2 بصارت کی جس آنکھ کے پہلے پردے ریٹینا میں ہوتی ہے.(The retina and not the lens in the eye is the photo receptor.)
3 امراض کے اسباب مریض کے علاوہ دیگر مقامات پر بھی تلاش کرنے چاہئیں.طب میں میں کتابیں تصنیف کیں.5 کتاب الکلیات اور ابو مروان ابن زہر کی کتاب استیسیر کے لاطینی تراجم اکھٹے ایک جلد میں انسائیکلو
پیڈیا کے طور پر شائع کئے.6 ارسطو کے فلسفے کے اصولوں کا طب پر اطلاق کیا.7 اس میں مشاہدے اور تنقید کی قوت بے حد تک ودیعت کی گئی تھی جو ایک سائنس داں کے لئے بنیادی چیز ہے.خلیفہ ابو یعقوب یوسف کا شاہی طبیب رہا.71
Page 90
باب چهارم بحیثیت سائنس داں عظیم فلسفی ، عبقری سائنس داں اور دقیقه شناس و نکتہ داں مفکر تھا.مشاہدہ نگاری کا یہ عالم تھا کہ جس چیز
کو دیکھتا گہری نظر سے دیکھتا.ہر مظہر قدرت میں خدا کی شان کا جلوہ تلاش کرتا اور کسی بات یا دلیل کو بلا حیل و حجت
تسلیم نہ کرتا.اس کا انداز فکر فلسفیانہ اور اسلوب محققانہ تھا.مطالعہ کا رسیا تھا، قرطبہ کی شاہی لائبریری اس کی پسندیدہ
جگہ تھی جہاں چار لاکھ کے قریب نایاب کتابوں کا علمی خزانہ موجود تھا.کسی مسئلے کے معائب و محاسن فوراً جان جاتا.ایک عبقری فلسفی ہونے کی وجہ سے اس نے ارسطو کے سائنسی نظریات کی گہرائی میں غوطہ زن ہو کر ان کو خوب سمجھا اور
ان کی تشریح کرتے ہوئے اپنا نقطہ نظر پیش کیا ، جس سے اس کی علمی فضیلت، مطالعے کی وسعت ، اور ژرف نگاہی
روز روشن کی طرح واضح ہوتی ہے.د و ارسطو کو مجسم دانش اور حکمت کا سر چشمہ سمجھتا تھا.(کتاب القیاس)
بعض لوگوں نے اس پر اعتراض کیا ہے کہ اس کی نظر میں سائنسی سچائی (scientific truth ) لوگوں کو
الہامی مذہب سے زیادہ تعلیم دے سکتی ہے.خاص طور پر کیتھولک چرچ نے یورپ میں یہ سنگین اعتراض بہت اچھالا
تھا.امر واقعہ یہ ہے کہ وہ تجزیاتی طریقے (analytical method) کے ذریعے مذہب کے عقائد اور پیغام کو بہتر
طریق سے سمجھنا چاہتا تھا.ذوق تحقیق انسان کو لذت تشکیک سے آشنا کر دیتا ہے اس لئے تحقیق کے دوران اگر اس کی
فکر رنگ تشکیک سے مزین ہوئی تو یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے.اس کا مطمح نظر مذ ہب اور عقل (یعنی سائنس) کے
ما بین تضاد اور تصادم کے بجائے ان کو ایک دوسرے کا مددگار ثابت کرنا تھا.اس کے نزدیک عقل ایمان کی مخالف
نہیں بلکہ تکمیل ایمان کا ذریعہ ہوتی ہے.قرآن حکیم کی آیات پر عقل کے ذریعے غور وفکر کرنے سے انسان حقیقت کا
ادراک کر سکتا ہے.یہ ادراک حقیقتاً اصل ایمان ہے.اس سے یہ مستنبط ہوا کہ معقل اور ایمان ایک دوسرے کے لیے
ممد و معاون ہیں.72
Page 91
کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ امریکہ کی دریافت کا آئیڈیا کرسٹوفر کولمبس کو اس کی تصانیف سے ملا تھا.کرسٹوفر کولمبس کا خود اپنا بیان ہے کہ امریکہ کی دریافت کی جانب جس چیز نے میری رہ نمائی کی وہ کی
تصانیف ہیں ( معرکہ مذہب و سائنس صفحه 223 ، بحوالہ کتاب مؤلفه مولوی محمد یونس فرنگی محل صفحه 110 ).میری رائے میں مصنف کو غلط نہی ہوئی ہے، دراصل ابن عربی نے فتوحات مکیہ (1232ء) میں فرمایا تھا کہ میں نے
بحر الکاہل کے اس پار کشف میں ایک ملک دیکھا تھا.اسی طرح ڈریپر نے اپنی کتاب یورپ کی ذہنی ترقی کی تاریخ Intellectual History of
Europe, by 1.W.Draper) میں صفحہ 39 پر لکھا ہے کہ قرص آفتاب (Sun Spots) میں دھبوں اور
داغوں کا انکشاف سب سے پہلے نے ہی کیا تھا (24).انٹرنیٹ پر کا ایک تجربہ دلچسپی سے پڑھنے کے لائق ہے.نے کہا کہ اگر ہم جو کے بیج کومٹی
میں ہوئیں اور اس کو ٹیوب میں رکھ دیں تو اس میں سے پورا نگلنا شروع ہو جائے گا، بھٹا اور اس کی جڑ بھی نظر آئے
گی.چنانچہ اس نے طالب علموں کو خود ایسا عموم کر کے دکھایا اور وہ حیران رہ گئے".(www.kul.lublin.pl/efk/angielski/hasla/a/averroes/html)
بحیثیت ہئیت داں
عبد وسطی کی سائنسی تاریخ کے ہر مصنف نے بلا استشمی اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ ایک مسلم
الثبوت نظریاتی اور مشاہداتی ماہر فلکیات (theoretical and observational astronomer) تھا.علم
فلکیات پر اس کے سائنسی نظریات کا اثر بہت گہرا اور دیر پا تھا.شاید کوئی کہے کہ قرطبہ کا قاضی ہیئت داں کیسے بن
گیا؟ دراصل بیئت پر اس نے تمام تحقیقی کام جوانی کے عالم میں کیا تھا.مثلاً جب اس نے 1153ء میں زندگی کے
ستائیسویں زینے پر قدم رکھا تو خلیفہ کی خواہش پر مراتش گیا جہاں اس
کو رصد گاہ کا مہتم (ڈائر یکٹر ) مقرر کیا گیا.اسی
رصد گاہ سے اس نے سن اسپانس یعنی قرص آفتاب میں دھبوں اور داغوں کا لمبے مشاہدات فلکی کے بعد انکشاف کیا
تھا.قرطبہ کی طرح مراقش
پہنچ کر بھی ستارہ بینی اور مشاہدات فلکی کا سلسلہ برابر جاری رہا.اس امر کا ذکر اس نے ارسطو
کی کتاب شرح السماء و العالم (De Caelo) میں کیا تھا.اس نے کہا " حرکات الافلاک میں مزید تحقیق کی
ضرورت ہے تا کہ فزیکل اسٹرانومی کی بنیاد رکھی جاسکے بجائے صرف ریاضیاتی اسٹرانومی کے.جب میں نوجوان تھا تو
میں نے اس موضوع پر تحقیق کرنے کے امکانات کا سوچا تھا لیکن اب جبکہ میں ضعیف ہو گیا ہوں ممکن نہیں ہے."
73
Page 92
علم فلکیات میں اس کے شوق اور ایک نامعلوم ستارے کی دریافت کا ذکر بھی ایک مغربی مصنف نے کیا ہے:
"Ibn Rushd, at the age of 27, made astronomical observations
near Marrakesh in the course of which he discovered a previously
unknown star." (25)
ترجمہ: نے ستائیس سال کی عمر میں مراتش کے قریب فلکیاتی مشاہدات کئے ، ان مشاہدات کے
دوران اس نے ایک نا معلوم ستارے کو دریافت کیا."
۱:
كتاب ما بعد الطبیعات (مینا فزکس) کی شرح میں اس نے کہا تھا: " جوانی کے زمانے میں مجھے امید تھی کہ
میں علم فلکیات پر اپنی ریسرچ مکمل کر سکوں گا.اب جبکہ میں ضعیف العمر ہوں میں نا امید ہو گیا ہوں کیونکہ میرے
راستے میں کئی رکاوٹیں نہیں.لیکن اس موضوع پر میں جو کچھ کہتا ہوں شاید مستقبل میں محققوں کی توجہ اس طرف
مبذول ہو.ہمارے دور کی فلکیات کی سائنس ان مسائل پر روشنی نہیں ڈالتی جس سے اصل حقیقت کا حال معلوم
ہو سکے.ہمارے زمانے میں جو (سائنسی ماڈل تیار کیا گیا ہے یہ ریاضیاتی طور پر تو ٹھیک ہے مگر حقیقت سے
مطابقت نہیں رکھتا."
اس اقتباس سے مترشح ہوتا ہے کہ وہ علم فلکیات کی نظریاتی تاریخ سے باخبر تھا.اس نے ارسطو کے سائنسی
نظریات کی وضاحت بڑے عمدہ اور مدلل طریقے سے کی ہے.وہ بطلیموس (Ptolemy) کے نظریات اور
پارکس (Hipparchus) سے پہلے جو قدیم ماہرین فلکیات گزرے ہیں، ان کے نظریات سے بھی واقفیت رکھتا
تھا.اس کے ساتھ ساتھ وہ عرب ماہرین ہیئت کی کتابوں کارناموں اور نظریات سے بھی اچھی طرح واقف تھا.یادر ہے کہ البانی اور ابن یونس بطلیموس کے پیروکار تھے مگر الفرغانی، الزرقالی اور البطر وجی نے بطلیموسی نظام پر تنقید کر
کے تبدیلیاں تجویز کیں.اگر چہ ماضی قریب اور اپنے دور کے ہیئت دانوں سے متاثر تھا مگر وہ ان کی اندھی
تقلید نہیں کرتا تھا.سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت دور بین اور ٹیلی اسکوپ جیسے آلات نہیں تھے تو اس نے یہ مذکورہ ستارہ کیسے
دریافت کیا ہو گا؟ ایک بات تو ظاہر ہے کہ وہ آسمان پر موجود دریافت شدہ ستاروں کے ناموں اور ان کے محل وقوع
سے واقف تھا.قرطبہ کے بجائے مراقش (افریقہ) میں ستاروں کا دیکھنا اس کے جغرافیائی محل وقوع کی وجہ سے زیادہ
آسان ہوگا.یہ بھی ظاہر ہے کہ وہ ستارہ بینی کے دوران ان کا ریکارڈ ضرور اپنی ڈائری میں رکھتا ہوگا اور ممکن ہے ان
ستاروں
کا کوئی کیٹیلاگ بھی تیار کیا ہو.74
Page 93
-1
بہ حیثیت ہئیت داں اس نے اجرام فلکی کو درج ذیل طور پر تقسیم کیا:
ایسے اجرام سماوی جو آنکھ سے نظر آ جاتے ہیں
2 ایسے اجرام سماوی جو آلات رصد کی مدد سے نظر آتے ہیں
3.ایسے اجرام فلکی جن کی موجودگی عقل ( تھیورنیکل ) سے ثابت ہوتی ہے.دوسری قسم کے اجرام سماوی مشاہدات فلکی کرنے والے سائنس دانوں کو بعض دفعہ کئی سالوں بعد نظر آتے
ہیں.نیز ان کو دیکھنے کے لئے کئی نسلوں کے درمیان باہمی تعاون و شرکت کی ضرورت ہوتی ہے مگر اس دوران
مشاہدات کرنے کے لئے آلات رصد بھی بدلتے رہتے ہیں.اس کی ایک مثال بیلیز کامٹ ( Haleys
Comet) ہے جو ہر ستر سال بعد نظر آتا ہے ).ارسطو نے حرکات الافلاک ( Concentric Spheres) کی کل تعداد 5 5 جتلائی تھی.کہتا ہے کہ
اس کی زندگی میں مسلمان ماہرین فلکیات نے یہ تعداد 50 ظاہر کی تھی لیکن نے اپنے علم اور تجربے کی بناء پر
یہ تعداد 45 کردی یعنی 38 غیر متحرک ستارے (fixed stars ) اور 7 ایسے اجرام فلکی ( سیارے ) جو یومیہ محوری
گردش کرتے ہیں.ان کی اصل تعداد کیا ہے؟ اس پیچیدہ سائنسی مسئلے کا حل پیش کرتے ہوئے اس نے کہا اس
سوال کے بغور جائزے میں کیا ضروری اور واقعی مسائل ہیں، ہم انہیں ان لوگوں پر چھوڑ دیتے ہیں جو خود کو اس علم
کے لئے وقف کر چکے ہیں اور جن کو دوسرے علوم سے کوئی سروکار نہیں ہے." بطلیموس کے الافـــاك
الخارجات المراكز ( system of eccentrics ) اور الافلاك التداویر ( epicycles) سے اتفاق
نہیں کرتا تھا (26).کتاب ما بعد الطبیعات کی شرح میں اس نے ثابت این قرہ کے نظریہ الاقبال والادبار
( Trepidation & Recessions) کی جو تو ضیح پیش کی ہے وہ ان مصنفین کے برعکس ہے جن کے نزدیک یہ
کائنات ہومو سینٹرک اسٹیئر ز ( Homocentric Spheres) سے بنی ہے.اس نے افلاک میں موجود اجرام
کے مشاہدے (یعنی رصد ) کی اہمیت بھی بیان کی.علم بحیت میں اس کی درج ذیل کتابیں قابل ذکر ہیں.تلخيص المجسطی - Summary of Almajest (اس کا لاطینی میں ترجمہ نہیں ہوا تھا )
مقاله في حركة الفلك.Motion of the Sphere
يحتاج اليه من كتاب اقليدس في المجطی.(اس
کا مخطوطہ اسکو ریال میں ہے )
مقاله في تدوير هيئة الافلاك والثوابت -
75
Page 94
یادر ہے کہ المجسطی اسکندریہ کے سائنس داں عظیموں کی علم فلکیات پر مبسوط جلیل القدر کتاب ہے، جس کا
مطالعہ 1400 سال تک ماہر ین ہیئت کرتے رہے.یہ کتاب اس نے 150ء میں لکھی تھی.اس کو بائیبل آف اسٹرانومی
بھی کہا جاتا ہے.یونانی زبان میں اس کا نام مینگالے پیتھیک سنیکس (Megale Mathematike Syntaxis)
تھا.اس کا مخفف مجسطی سنیکس (Magiste Syntaxis) ہے.عرب مترجمین ( الحجاج ، الحق ابن حنین ، ثابت
ابن قرة ) نے نویں صدی میں جب اس کا ترجمہ بغداد میں کیا تو اس کا نام المجسطی (The Greatest) رکھ دیا
جو آج تک مروج ہے.یونانی زبان میں مکمل کتاب تو کب کی نا پید ہو چکی ہے.دنیا بغداد کے مسلمانوں کی رہین
منت ہے جنہوں نے اس کا عربی میں ترجمہ کر کے رہتی دنیا تک کے لئے اس نایاب علمی خزانے کو محفوظ کر دیا
سیکڑوں سائنس داں اس کے مطالعے سے اپنے ذہنوں کو جلا بخش چکے ہیں.یونان میں یہ آخری بار 1913ء میں
زیور طبع سے آراستہ ہوئی تھی.نے اس کی جو تلخیص سپرد قلم کی تھی اس کا عبرانی میں ترجمہ جیکب انا طولی
( Jacob Anatoli) نے 1231ء میں کیا تھا.کتاب کے مطالعہ سے بطور سائنس دان کی علمی حیثیت
مسلم ہوتی ہے جس نے اس قدر مشکل کتاب کو سمجھا اور خلاصہ تیار کیا.تلخیص کی تیاری بھی مہارت فن کا اظہار ہے.کوئیز یونیورسٹی کی ڈگلس لائبریری میں اس کا عربی سے انگلش ترجمہ بمع حواشی موجود ہے، جو پہلی بار 1984ء
میں لندن سے شائع ہوا تھا.یہ ترجمہ 693 صفحات پر مشتمل ہے.اس کے تیرہ ابواب ہیں.کتاب میں اسٹار
کیٹلاگ کے علاوہ آلات ہیت بھی دئے گئے ہیں.اس کتاب میں اس نے زمین کو کائنات کا مرکز قرار دیا تھا اور
اس کے تین ثبوت دئے تھے.اس نے یہ بھی کہا تھا کہ زمین گردش نہیں کرتی ہے (27).مقاله في حرکت الفلک کے ضمن میں یہ بتادینا ضروری ہے کہ تفسیر ما بعد الطبيعة (صفحہ
1664) میں اس نے کہا تھا کہ جب میں نو جوان تھا تو اس موضوع پر شرح وبسط سے تحقیقات کا ارادہ تھا مگر اب
بڑھاپے میں پہنچ کر مایوس ہو گیا ہوں.ممکن ہے اس نے اس سائنی مسئلہ پر کافی غور و خوض کیا ہوا اور جب اس کا کوئی
حل نہ مل سکا تو مزید تحقیقات کا ارادہ ترک کر دیا.سائنس دانوں کے ساتھ ایسا ہوتا رہتا ہے.ضروری نہیں کہ ہر اس
سائنسی مسئلہ کے جس پر ریسرچ شروع کی ہے خاطر خواہ نتائج بھی حاصل ہوں.اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سائنس داں سو
نظریات وضع کرتے ہیں مگر ان میں صرف پانچ ٹھیک ثابت ہوتے ہیں.تقریباً سو سال قبل 1911ء میں روم سے عربی زبان میں کتاب علم الفلك ، تاريخه عند العرب في
القرون الوسطى شائع ہوئی تھی جس کا ایک نسخہ میری ذاتی لائبریری میں موجود ہے اس کے مصنف پروفیسر کارلو
نالینو ( Carlo Nallino) نے علم فلکیات کی یہ اقسام بیان کی ہیں: علم البيئية الكروى علم البعيد النظري علم الميكا
نیتہ الفلكية علم طبعة الاجرام الفلكية - علم البیعیة العملی.آخری قسم یعنی پریکٹیکل اسٹرانومی کی تفصیل دیتے ہوئے
76
Page 95
.مصنف نے کا ان الفاظ میں تذکرہ کیا ہے:
" وهو جزء ان جزء رصدی مشتمل على نظرية الالآت الرصدية وكيفية الارصاد
وقياس الزمن.وجزء حسابي يعلم طرائق حساب الزيجات والتقاويم وغير ذالك على
قواعد النظريات المثبة فى الاقسام الاولى و اضيف الى ذلك ان الجزء الرصدي من هذا
القسم هو ما يسميه الفيلسوف الاندلسي الشهير ابو الوليد الحفيد المتوفي سنة
۱۱۹۸ صناعة النجوم التجريبيية (كتاب ما بعد الطبيعة ص ٨٣ من طبعة مصر (١٩٠٣ء) قانه
يمى سائر اجزاء علم الهئية صناعة النجوم التعاليمية ابى المبنية على التعاليم وهي
الرضيات" ( صفحه (۲۲)
(مصنفه السنيور كرلو نلينو الاستاذ بالجامعة المصرية و بجامعة بلروم با يطاليه.طبع مدينة روما العظمى سنة ١٩١١ء) - (28) اور بطلیموس
اسی طرح ایک اور مصنف پروفیسر جارج صلیبیا، کولمبیا یونیورسٹی، نیو یارک ، اپنی کتاب ہسٹری آف عربک
اسٹرانومی میں کہتا ہے کہ جن لوگوں نے بطلیم ہیں (Ptolemy) کی اسٹرانومی پر کڑی تنقید کی ان کے دو گروپ تھے
ایک گروپ جس نے صرف اس کی اسٹرانومی پر تنقید کی مگر اس کا کوئی متبادل نظام پیش نہیں کیا.دوسرے وہ لوگ تھے
جو اس کے متبادل نظام کا خود کوئی ریاضیاتی ماڈل (Mathematical Model) پیش نہیں کر سکتے تھے تا کہ ان کی
فلسفیانہ جستجو اور سوالوں کے جواب مل سکیں.وہ جو ریاضی کے امور میں خود ماہر تھے اس لئے انہوں نے بطلیموں نظام
پر تنقید سائنسی نقطہ نظر سے کی اور بطلیموی نظام کو ریاضی کے اصولوں پر تعمیر کرنے کی سعی کی.وہ سائنس داں جنہوں نے فلسفیانہ نقطہ نظر کو مد نظر رکھ کے تنقید کی ان میں سے زیادہ تر کا تعلق اندلس سے تھا.جیسے ابن باجہ (1139ء ) ابن طفیل (1185ء) (1198ء ) البطر و جی (1200ء).ان سائنس دانوں کی
کوشش تھی کہ کسی طرح وہ ارسطو کے نظام بیت کی احیائے ثانی کر سکیں.وہ کسی ایسے نظام ہئیت کو قابل قبول نہیں سمجھتے
تھے جو ارسطو کے مفروضوں سے میل نہ کھاتا تھا.ان کا بطلیموسی نظام ہئیت پر بڑاعتراض یہ تھا کہ اس میں الافلاک
الخارجات المراکز اور الافلاک اتمد اور موجود تھے.(29)
ایک اور جگہ یہی مصنف کہتا ہے کہ اسلامی دنیا کے مشرقی ممالک میں ابن سینا اور اس کے شاگرد ابو عبید الجوز جانی
77
Page 96
نے بطلیموس کے سیاروں کے مدار سے متعلق مسئلہ ایکیوٹینٹ Problem of Equand) کا نیا حل پیش کرنے کی
کوشش کی تھی تا کہ اس کے نظام کی ریاضی اور طبعی ضروریات کو مطمئن کیا جاسکے.جوز جانی نے ایک رسالے میں لکھا
ہے کہ ابن سینا نے اس کو بتلایا کہ میرے پاس اس کا حل موجود ہے لیکن ابن سینا نے یہ حل اسے دکھا یا نہیں تھا.اس
صدی میں ابن الہیشم ( مصر ) نے ایک مقالہ الشكوك على بطليموس لکھا جس میں اس نے بطلیموس کے
نظام بحیت پر مدلل علمی اعتراضات کئے اور اس میں موجود تضادات کو واضح کرتے ہوئے بطلیموس کے متبادل نظام
کے لئے کچھ شرائط کا ذکر کیا.ابن الہیشم کے چیلنج کے جواب میں اندلس کے مشہور ہیئت داں جیسے ابن باجہ ( ساراگوسا)، ابن طفیل
(غرناطه ) ، ( قرطبہ) البطر وجی (اشبیلیہ1204ء) اور جابر ابن افلح (اشبیلیہ 1200ء) نے بطلیموس
کے نظام ہئیت کو از سر نو مرتب (reformulate) کرنے کی کوشش کی.کیا یہ ماہرین ہیئت ابن الہیشم کے چیلنج کے
جواب میں ریسرچ کا کام کر رہے تھے؟ یہ قطعی طور پر معلوم نہیں ہو سکا البتہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی ریسرچ کا محرک
شائد یہی تھا.کو پرٹیکس ان اندلی ماہرین ہیئت کی ریسرچ سے اچھی طرح
آگاہ تھا.کو پرنیکس نے ان کی ریسرچ
سے کس حد تک استفادہ کیا اس کا قطعی علم اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک ان
کی عربی اور لاطینی میں موجود کتابوں
کو دوبارہ ایڈٹ (edit) نہیں کیا جاتا.(30) علم نجوم پر یقین نہیں رکھتا تھا بلکہ اس نے اس کو مکمل طور پر رد کیا.اس نے لکھا ہے:
"It does not belong to physical science; it is only a prognostication of
future events, and is of the same type as augury and vaticination." (31) کے علاوہ کئی دیگر مسلمان سائنس داں بھی علم نجوم پر یقین نہیں رکھتے تھے.ہاں علم فلکیات کی افادیت
اسلامی نقطہ نظر سے علما اور فقہا سب پر عیاں تھی مثلاً اس کے ذریعے یعنی مکہ مکرمہ کا رخ کسی علاقے سے تلاش کرنا ،
رمضان المبارک کے مہینہ کے آغاز کا تعین ، اسلامی تہواروں (حج) کا تعین ، نمازوں کے اوقات کا تعین، وغیرہ.یادر ہے کہ مساجد میں مواقیت الصلوة (Time Keeper) کا سلسلہ اسی طرح شروع ہوا تھا.جیسا کہ گزشتہ صفحات میں ذکر کیا گیا کہ مشرق کے اسلامی ممالک میں ابن سینا نے پرابلم آف ایکوئیٹ پر
غور و خوض کے بعد اس کا حل پیش کیا تھا.اندلس میں اس مسئلے پر جابر ابن افلح نے تحقیقی کام کیا اور بطلیموس پر تنقید
کرتے ہوئے کیا:
78
Page 97
"He did not take the center of the deferent (in the model of the upper
planets) to be halfway between the equant and the center of the universe
without proof".نے بھی اس سائنسی مسئلہ پر ریسرچ کی تھی:
"He blamed Ptolemy for not being Aristotelian enough, taking him to task
mainly in the context of his own commentary on Aristotle's
Metaphysics." (Page 75)
غرضیکہ بطلیموس کے نظام بحیت کا متبادل نظام پیش کرنے یا اس میں اصلاح کرنے میں جن اندلسی ماہرین
بیت نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ان میں درج ذیل نام قابل ذکر ہیں: المطر و جی اور جابر ابن الصلح.یہاں دو
مؤخر الذکر ہیئت دانوں کے مختصر حالات زندگی پیش کئے جاتے ہیں :
نورالدین البطر و جی (1204ء) اپنے دور کا نا میر اور ممتاز ہئیت داں تھا.اس کی تصنیف کتاب فی الهیئته
کا ترجمہ مشہور مترجم مائیکل اسکاٹ نے 1217ء میں ٹولیڈو میں کیا.برکلے، امریکہ سے یہ 1952ء میں شائع ہوا.عبرانی میں اس کا ترجمہ دی آتا ہے 1531ء میں طبع ہوا.اسطر و جی فلکی مشاہدات کرتے ہوئے انسانی حواس پر زیادہ
اعتبار نہیں کرتا تھا کیونکہ مشاہدہ کرنے والے اور ملکی کروں کے مابین فاصلہ بہت
لسا تھا.کو پر ٹیکس کے دور تک یورپ
کے عالموں پر اس کے سائنسی نظریات کا گہرا اثر تھا.کوپرنیکس نے اس کا ذکر اپنے علمی شاہکار ڈی ریود لیونی بس
( De Revolutionibus) میں کیا ہے اس کے زبر دست علمی اور سائنسی کارناموں کے پیش نظر چاند کا ایک حصہ
مارے نیک نارس ( Mare Nectaris) اس کے نام سے منسوب ہے.کتاب فی الهئیته کا انگریزی ترجمہ
عربی متن کے ساتھ برنارڈ گولڈ اسٹین نے Al-Bitnji: On Principles of Astronomy کے عنوان
سے امریکہ سے 1971ء میں شائع کیا تھا.جابر ابن افلح (وفات 1200ء) بارہویں صدی کا سب سے افضل ہیت داں اور ریاضی داں تھا.اس کی عمر کا
زیادہ حصہ اشبیلیہ میں گزرا.اس کا علمی شاہکار اصلاح المجسطی تھا.اس کا عربی قلمی نسخہ برلن لائبریری
میں موجود ہے.اس کتاب کی زبر دست افادیت کے پیش نظر جیرارڈ آف کر یہونا نے اس کا ترجمہ لاطینی میں کیا.1274ء میں اس کا ترجمہ عبرانی میں کیا گیا.اس کتاب میں جابر نے بطلیموس کے بہیت کے نظریات پر کڑی تنقید کی
اور اس کے کئی نظریات سے اختلاف کر کے متبادل نظریات پیش کئے.بطلیموس کی بیان کردہ غلطیوں کو اس نے واضح
79
Page 98
طور پر بیان کیا.اشبیلیہ کے ٹاور لاجیرالڈا (La Geralda) جو کبھی جامع مسجد کا مینارہ ہوا کرتا تھا ، میں رات کے
وقت گھنٹوں تنہائی میں بیٹھ کر اس نے کئی سال تک فلکی مشاہدات کئے.راقم السطور نے یہ تین سوفٹ اونچاد دکش مینارہ
1999ء میں اپنین کی سیاحت کے دوران دیکھا تھا.مینار کے اندر سیٹرھیوں کے بجائے ریمپ ( ramp) ہے
چنانچہ موزن گھوڑے پر سوار ہو کر آخری منزل پر جا کر اذان دیا کرتا تھا.آخری منزل پر چاروں رخ کھڑکیاں ہیں
جن سے ملحق بالکونی بنی ہوئی ہے اس لئے انسان اونچے مقام سے باآسانی آسمان کا مشاہدہ رات کے وقت کر سکتا
ہے.اس کی تصنیف کتاب الهئیته میں ایک باب اسفیریکل اسٹرانومی (Spherical Astronomy) پر ہے
جس سے یوروپ میں نزیگنیومیٹری کے علم میں توسیع ہوئی.1970ء میں مانچسٹر یو نیورسٹی ( برطانیہ ) میں ایک
طالب علم آر پی لارچ R) P.Lorch) کو جا بر اینڈ ہر انفلوئیس ان دی ویسٹ Jaber and His)
Influence in the West مقالہ لکھنے پر ڈاکٹریٹ کی ڈگری دی گئی.میں نے مسٹر لا رچ سے 2004 ء میں
ای میل کے ذریعے رابطہ قائم کیا تا کہ یہ مقالہ حاصل کر سکوں، لیکن مائیکر فلم پر ہونے سے ایسا ممکن نہ ہو سکا.ایک اور مصنف کی رائے
مصنف ٹامس گلک (Glick) کہتا ہے کہ اندلس کی تصیور نیکل اسٹرانومی کا ایک خاص فیچر یہ تھا کہ وہاں کے
بیت واں ارسطو کے نظام کو بطلیموس کے نظام پر ترجیح دیتے تھے.البطر و جی چاہتا تھا کہ بطلیموسی نظام میں سے
الافلاک الخارجات المراکز اور الافلاک احمد اویر (epicycle) کو خارج کر کے ان کی جگہ کرے (spheres ) رکھ
دئے جائیں.ابن باجہ اور ابن طفیل بھی افلاک امدادیر کے خلاف تھے.جبکہ الافلاک الخارجات المراکز اور
الافلاک
الند اور کے خلاف دلیل یہ دیتا تھا کہ " بطلیموس سے پہلے کے موجود علم ہیت کا بحال کیا جانا لازمی تھا کیونکہ
وہی تو اصل علم بعیت تھا جو طبیعی قوانین کے نقطہ نظر سے قابل اعتبار تھا."
Pre-Ptolemaic astronomy had to be retrieved, for it is the true astronomy
that is possible from the standpoint of physical principles.(32) اور نیوٹن
اسٹیٹ یونیورسٹی آف نیو یارک کے سابق پروفیسر ویرین بولوگ (Vern Bullough) نے اپنے مضمون
Medieval Scholastics and Averroism میں لکھا ہے کہ قرون وسطی کی پیڈ وایو نیورسٹی (اٹلی) میں
80
Page 99
متعدد پروفیسروں نے منطق کے اصولوں کا اطلاق میڈیسن پر بالکل ویسے ہی کیا جس طرح ابن سینا اور نے
کیا تھا.اس کا ضمنی فائدہ یہ ہوا کہ سائنس میں ایک نئے طریق کار کا آغاز ہوا جسے ریزولیوشن اینڈ کمپوزیشن
(Resolution & Composition) کا نام دیا گیا.ماڈرن سائنس کی ترویج میں اس طریق کار کا بہت بڑا
ہاتھ ہے کیونکہ اس میں تجربے کی اہمیت پر بہت زور دیا گیا.ارسطو کا کہنا تھا کہ سائنسی حقائق کی دریافت کے لئے
مشاہدہ ہی کافی ہوتا ہے مگر اس طریق کار میں حقیقت کے مشاہدہ سے کام شروع کر کے اس کو اجزائی حصوں میں
ریز الو کیا جاتا تھا.مثلاً بخار کی وجوہات: بخار کسی مائع کے گرم ہونے سے یا کسی عضو کے گرم ہونے سے ہو سکتا ہے،
پھر مائع کے گرم ہونے کی وجہ یا تو خون ہے یا پھر بلغمی مادر، یوں کرتے کرتے انسان بخار لاحق ہونے کی خاص وجہ یا
پھر بخار کی اصل حقیقت اور وجوہات کا علم حاصل کر لیتا ہے.(1) اس سائنسی اصول کے ماتحت کی بعض نظریات (تھیوریز) کو پر کھا گیا مثلاً اس نے تھیوری
آف کلر (Theory of Colour) وضع کی جس کے مطابق رنگوں کے لئے دو جڑواں متضاد خواص کا مختلف
کمیتوں میں ہونا ضروری ہے جیسے منور اور مدھم محدود اور غیر محدود:
Averroes developed a theory of colour which held that colors were
attributed to the presence in varying degrees of two pairs of opposite
qualities: brightness and obscurity, bounded and unbounded.اس تھیوری کے مد نظر بہت سے سائنس دانوں بشمول آئزک نیوٹن نے اپنی تھیوریز کو پرکھا اور پھر اس کے جواب میں
اپنی تھیوری آف کلر پیش کیں.(2) نے مقناطیسی جاذبیت پر تحقیق کی تھی جس کی تشریح انواع کی بڑھوتری کی گئی.کیونکہ مقناطیس کو
جو چیز چھوتی ہے اس کے اجزاء یا خواص میں تبدیلی آجاتی (جیسے پانی اور ہوا) پھر لوہے کے پاس پڑے اجزاء تبدیل ہو
جاتے جن کے ایٹم میں حرکت پیدا ہوتی اور یہ مقناطیس کی طرف لپکتے ہیں.جان فیراڈے اور میکس ویل نے جو ٹیوبز
آن فورس ( Tubes of force ) کئی سوسال بعد برطانیہ میں بنائی تھیں وہ اس کے مشابہ تھیں.تاہم کی
دریافت نیز فیراڈے اور میکس ویل کی دریافت کے مابین کسی نے ابھی تک براہ راست ربط ثابت نہیں کیا:
"Averroes had also investigated the problem of magnetic attraction and
this had been explained as a form of multiplication of species.That is, the
lodestone modifies the parts of the medium touching it (air or water), and
81
Page 100
these then modified the parts next to the iron.in which a motive virtue
was produced, causing it to approach the lodestone."
(3) نے علم جنین (Embryology) پر بھی تحقیق کی تھی.اس موضوع پر یورپ میں سب سے
پہلی کتاب جائز آف روم 10-13-1247 Giles of Rome) نے لکھی تھی اور اس سوال کہ انسانی جسم میں
روح کب پیدا ہوتی ہے، پر مدلل طریق سے روشنی ڈالی تھی.کا نظریہ تھا کہ روح جسم کے ساتھ ہی پیدا ہوتی
ہے لیکن نمو پانے والا بچہ ( جنین ) جب حرکت کرنا شروع کرتا ہے تو یہ اپنی موجودگی کا اظہار کرتی ہے.یہ آئیڈیا
عیسائیت نے انیسویں صدی میں قابل قبول تسلیم کیا تھا.کا نظریہ تھا کہ انسانی مادہ تولید میں اتنی خلقی استعداد موجود ہے کہ اس سے ہونے والے بچے کے خط و
خال، اس کی پرورش اور اس کے اعضاء کی نشو و نما کر سکے.(A potentiality exists in the semen that determines the shape of the
offspring, its nourishment, and development of its organs)
(4) کے سائنسی نظریات نے اطالوی سائنس دانوں جیرارڈ و برونو 1600-1547 Bruno)
اور گیلی لیو 164-1564 Galileo) کو بہت متاثر کیا تھا کیونکہ دونوں نے ایسے سائنس دانوں کے ہمراہ تعلیم
حاصل کی تھی جو یو نیورسٹی آف پیڈ وا (اٹلی) میں کے نظریات کے پر جوش پیروکار ( Averroists ) تھے.این رشد کے پیروکاروں کے علمی اثر کی وجہ سے سترھویں صدی میں ارسطو کے نظریات میں تنزل آگیا.عجیب اتفاق
ہے کہ ارسطو کا سب سے بڑا پر چار کرنے والا تھا مگر اس کے پیرو کاروں نے ارسطو کا علمی اثر یورپ میں زائل
کیا.کے نظریات کا اثر یورپ میں چاہے منفی تھا یا ثبت یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ یورپ میں نئی روشنی
کی تحریک (Enlightenment ) بر پا کرنے میں اس کا بہت بڑا ہاتھ تھا (33).گیلی لیونے کے سائنسی
نظریات سے کس حد تک استفادہ کیا اس کا اعتراف امریکی مصنف عمولس ریشر (Nicholas Rescher) نے
ان الفاظ میں کیا ہے:
"The Averroist tradition of Padua kept alive the Arabic interest in and
spirit of inquiry respecting natural science, until the time that it provided
intellectual grist to the mill of Galileo and his teachers." (34)
(یعنی " پیڈو کی رشدی تحریک کی روایت نے نیچرل سائنس میں عرب دلچسپی اور تحقیقات کی روح کو زندہ رکھا حتی
82
Page 101
کہ اس نے میلی لیو اور اس کے اساتذہ کی مل کو علمی غذا فراہم کی.قرطبہ کا زلزلہ
جیسا کہ ذکر کیا گیا کہ میں مشاہدے کی قوت غیر معمولی حد تک ودیعت کی گئی تھی.اس کی مثال
قرطبہ کا وہ زلزلہ ہے جو 1170ء میں آیا.اس وقت اشبیلیہ میں مقیم تھا.قرطبہ کے شہریوں نے مشاہدہ کیا
کہ زمین نے کس شدید قوت سے حرکت کی کہ ہر طرف ہلچل مچ گئی.گویا قیامت ٹوٹ پڑی.نے جو کچھ
مشاہدہ کیا وہ اس طرح تھا." میں مین وقت پر قرطبہ میں موجود نہیں تھا لیکن جب میں وہاں پہنچا تو میں نے ایسی
گڑگڑاہٹ کی آوازیں نہیں جو زلزلہ سے پہلے آتی ہیں.لوگوں نے دیکھا کہ گڑگڑ کی آواز قرطبہ کے مغرب کی طرف
سے آئی اور اس کے ساتھ ہی زلزلہ سے جو خوفناک آندھی چلی وہ بھی مغرب کی جانب سے آرہی تھی.دہشت انگیز
زلزلے کے خفیف جھٹکے (Siesmic T remors) قرطبہ میں اگلے سال تک آتے رہے اور تین سال تک ایسا
ہوتا رہا.پہلے زلزلے میں بہت سارے لوگ مارے گئے اور ان کے گھر منہدم ہو گئے.کہتے ہیں کہ قرطبہ کے نزدیک
ایک مقام اندو جارا پر زمین شق ہو گئی اور اس میں سے راکھ اور ریت سے ملتی جلتی چیز ہوا میں اڑنے لگی.جس کسی
نے یہ (زلزلہ ) خود دیکھا وہ اس کی صداقت پر یقین رکھتا تھا.زلزلہ بالعموم اندلس کے جزیرہ نما کے مغربی حصہ میں
زیادہ محسوس کیا گیا لیکن یہ سب سے زیادہ زور دار قرطبہ اور اس کے گردو نواح میں تھا.قرطبہ کے مشرقی حصہ میں یہ
شہر کے اندرون کے مقابلہ میں زیادہ زور کا تھا ، جبکہ مغرب میں یہ بہت ہلکا تھا.(تلخیص آثار العلویہ Meteorology 64، اقتباس از www.muslimphilosophy.com/Averroes) بائبل میں مذکور تخلیق کے نظریے سے اتفاق نہیں کرتا تھا.اس نے اسلامی نقطہ نظر سے تخلیق کائنات کا
نیا نظریہ پیش کیا.اس کا یقین تھا کہ خدا ازل سے ہے.خدا ہی محرک اول (Prime Mover ) ہے.وہ قرآن
مجید کے ہر لفظ ، ہر شوشہ پر صدق دل سے ایمان رکھتا تھا.اور کہتا تھا کہ قرآن کی آیات کے مطالب دو طریق سے سمجھنا
چاہیے.عام انسانوں کو صرف اس کے لفظی معنی بتلائے جائیں.فلسفیوں اور دانش وروں کے لئے اس کی پر معارف
آیات میں دوسرے معنی پوشیدہ ہیں جو فلسفہ سے مطابقت رکھتے ہیں، اس لئے حکیم ( فلسفی ) کو چاہئے کہ وہ قرآن
مجید کی آیات کی تاویل کرے مگر سادہ لوح لوگوں کو نہ بتلائے.اس کے نزدیک خدا کا علم ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز
( جزئیات ) پر بھی حاوی ہے کیونکہ خدا نے ہی تو ان اشیاء کو بنایا ہے.کتاب الحیوان کی تفسیر لکھتے ہوئے اس نے قرطبہ کی آب و ہوا کے اثر کا مطالعہ انسان کے بالوں، بھیڑ کی
83
Page 102
کھال اور لوگوں کے مزاج پر کیا.اسی طرح کتاب میٹر یولوجی کی تفسیر لکھتے ہوئے اس نے اظہار خیال کیا کہ عربوں
کی اولاد نے اسپین کے آزاد خطہ زمین میں آباد ہو کر رفتہ رفتہ مقامی لوگوں کی ذہنیت اختیار کر لی ہے.کتاب
الکلیات میں اس نے قرطبہ کے دریاداری الکبیر کے پانی کو خالص اور صحت کے لئے اچھا بتایا ہے.کا نظریہ ارتقا
نظریہ ارتقا کے بارے میں اس کا خیال تھا کہ کائنات مسلسل ارتقا پذیر ہے، یعنی جو کچھ دنیا میں موجود ہے وہ ہر
لحہ یا وقت کے ساتھ نئی صورتیں اختیار کرتا رہتا ہے.وہ کہتا تھا کہ خدا زمان و مکان کی قیود سے ماوراء ہے اور
رب العالمین کی تخلیق کا عمل برابر جاری و ساری رہتا ہے.خدا نے ہی زمان و مکان
کو بنایا.اس نظریے کی صراحت
کرتے ہوئے اس نے خدا کے ازل سے ہونے اور کائنات کے ازل سے ہونے کے فرق کو واضح کیا.اس نے کہا
ازل دو قسم کا ہوتا ہے ایک تو وہ جس کا سبب ہو یعنی ( eternity with cause ) اور دوسرے وہ ازل جو بغیر علت
کے ہے ( eternity without cause ).کائنات ازل سے ہے کیونکہ اس کا پیدا کرنے والا ازل سے اس پر
اثر انداز ہے.قادر مطلق خدا اس کے برعکس بغیر وجہ کے ازل سے ہے.خدا کی ذات کے ہونے میں زمان کا کوئی
دخل نہیں کیونکہ خدا زمان کے بغیر ازل سے قائم و دائم چلا آ رہا ہے.جارج سمارٹن نے گزشتہ چند سطور میں بیان کردہ
مضمون کو اس طرح ادا کیا ہے:
"Ibn Rushd tried to reconcile the Aristotelian notion of the cternity of the
world, which seems to imply a denial of creation, with
Muslim
creationism.God is eternal, and His creative effort is perpetual; He
creates time (or duration) as well as the world; and He may have created it
from eternity." (35)
چارلس سنگر نے کتاب " اے شارٹ ہسٹری آف سائنٹیفک آئیڈیاز میں کے نظریہ ارتقا کو یوں
بیان کیا ہے:
"Averroes believed, not in a single act of creation, but in a continuous
creation, renewed every instant in a constantly changing world, always
taking its new form from that which has existed previously."
84
Page 103
(یعنی این رشد تخلیق کے یک بارگی عمل پر یقین رکھنے کے بجائے تخلیق کے مسلسل عمل پر یقین رکھتا تھا جس کی
تجدید تغیر پذیر کائنات میں ہرلمحہ ہورہی ہے.یہ تخلیق ہر دفعہ ہی صورت میں انہیں اشیاء سے ہوتی ہے جو اس کا ئنات
میں پہلے سے موجود ہیں.)
"For Averroes the world, though eternal, is subject to an eternal Mover
constantly producing it and is eternal.This Mover can be realized by
observation of the eternal celestial bodies whose perfected existence is
conditioned by their movement."
(ترجمہ : کے نزدیک اگر چہ یہ کائنات ازل سے ہے، لیکن یہ ایک محرک (خدا) کے ماتحت ہے جو اس کی
تخلیق مسلسل کرتا ہے، نیز وہ کائنات کی طرح ازل سے ہے.اس محرک (خدا) کا احساس ہمیں ازل سے قائم اجرام
فلکی کے مشاہدے سے ہو سکتا ہے جن کا کامل وجود ان کی گردش پر مشروط ہے.)
"Thereby amy be distinguished two forms of eternity, that with cause
and that without cause.Only the Prime Mover is eternal and without
cause.All the rest of the universe has a cause, or, as we should say
nowadays, is 'subject to evolution'.He pictured the universe as finite in
space."
( ترجمہ ازل دو قسم کا ہے، ایک تو وہ جس کی علت ہے اور دوسرے وہ جو بغیر علت کے ہے.صرف محرک اول
( خدا ) از لی اور علت کے بغیر ہے.باقی تمام کائنات کی علت ہے، یا پھر جیسا آجکل کہا جاتا ہے کہ کائنات ارتقا پذیر
ہے.کے تصور میں کائنات خلاء کے اندر محدود تھی.) (36)
وقت کیا ہے؟
زماں یا وقت (Time) کے متعلق اس کا نظریہ تھا کہ وقت اور حرکت آپس میں اس قدر پیوست ہیں کہ ہم
وقت کے تصور کے بغیر حرکت کا تصور نہیں کر سکتے.خاص طور پر انسانی حواس سے اگر حرکت کا اور اک نہیں کیا جاسکتا
تو وقت کا ادراک بھی نہیں کیا جا سکتا جیسا کہ ارسطو نے سارڈینیا کے سلیپرز (Sleepers of Sardinia) کا ذکر
کیا یا قرآن مجید میں اصحاب کہف کا ذکر کیا گیا ہے.زماں حرکت کے ہو بہو نہیں ہے، یہ بات کے نزدیک
85
Page 104
ظاہر وباہر ہے.ہم وقت کا تصور حرکت کے بغیر نہیں کر سکتے اگر چہ حرکت کا تصور وقت کے بغیر کر سکتے ہیں.وقت کا
ادراک خاص طور پر رفتار کی نسبت سے حاصل کیا جا سکتا ہے جس کے اجزاء قبل اور بعد ہیں.جب ہمیں اس لمحہ
(Now) کا ادراک نہیں ہوتا تو ہمیں وقت کا بھی اور اک نہیں ہوتا.یعنی وقت کے ادراک کا حرکت کی تقسیم ( قبل
اور بعد ) سے چولی دامن کا ساتھ ہے.اس لئے ارسطو نے وقت کی تعریف نمبر آف موشن ( Number of
Motion) کی ہے، قبل اور بعد کے تعلق ہے.کے اس نظریے کی جھلک گیلی لیو اور نیوٹن کے زماں اور
حرکت سے متعلق سائنسی نظریات میں دیکھی جاسکتی ہے.(37) کا عقل کا نظریہ ( Theory of Intellect) یہ تھا کہ ہم اشیاء کے پیچھے پوشیدہ صورتوں کا عکس
بنا کر سوچتے ہیں:
"He believed that man thinks by abstracting the forms behind things and
that human intellect is receptacle of these intelligible forms."
آنکٹا مکین نے اس بات سے اتفاق کرتے ہوئے کہا:
"Imagination is more important than knowledge." کی غلطی نے ارسطو کے افلاک کے اسٹیئر بینڈ ماڈل ( Sphere-based Model) کی تائید کی تھی برعکس
بطلیموس کے ماڈل کے جس کا مرکز زمین تھی اور جو اس نے سائیکلک اور اوپی سائیکلک آرٹس ( & Cyclic
Epicyclic Orbits) سے وضع کیا تھا.ارسطو نے کا ؤنٹر ایکٹنگ اسفیرز ( Counter Acting
Spheres) کا ذکر کیا تھا جس کا عربی میں ترجمہ لولا بیا کیا گیا تھا.نے اس کے معنی کمانی دار، اسپائرل
(spiral ) کے کئے جس کی وجہ سے اس سے سنگین غلطی سرزد ہوئی کیونکہ کشش ثقل والے اجرام فلکی یقیناً کمانی دار
نہیں ہوتے.www.2nca.org/he/heta01.501p63.pd) اور سائنٹیفک ریوولیوشن
فلسفہ چونکہ تجربہ و مشاہدہ کی صداقت پر مبنی ہوتا ہے اس لئے یہ حقیقت جاننے کا سب سے معتبر ذریعہ ہے.اسلامی دنیا میں علما و فلاسفہ نے علم و حکمت کی بنیادیں تجربہ و مشاہدہ پر رکھی تھیں.یورپ میں احیاء علوم یا نشاۃ ثانیہ کا
آغاز اس وقت ہوا جب مسلمان مصنفین کی تصانیف کے ذریعے ان پر تجربہ و مشاہدہ کی اہمیت آشکارا ہوئی.اس لئے
86
Page 105
یہ کہنے میں مبالغہ نہیں کہ یورپ میں احیائے ثانی اسلامی علوم کا مرہون منت ہے.بیسویں صدی کے آخر میں لوگوں کو احساس ہوا کہ یورپ میں ہونے والے سیاسی انقلابات کے علاوہ سائنسی
انقلاب کے بارے میں علم حاصل کریں.یہ انقلاب دو سو سال یعنی 1500-1700ء کے عرصہ میں ظہور پذیر
ہوا تھا.عیسائیت کے آغاز کے بعد مغربی تہذیب کی تاریخ میں صحیح معنوں میں رخ بدلنے والا یہی انقلاب تھا.اگر چہ مغربی تہذیب پر عبرانی اور یونانی تہذیب کا اثر بہت نمایاں تھا مگر اس سائنسی انقلاب سے جنم لینے والی سوسائٹی
اس سوسائٹی سے بہت مختلف تھی جو اس سے پہلے تھی.کو پر ٹیکس کیپلر ، گیلی لیو، ڈیکارٹ اور نیوٹن کے جلیل القدر
سائنسی کارناموں نے ایک نئی علمی دنیا کو جنم دیا.موجودہ زمانہ میں اس انقلاب کے آنے سے پہلے کے پس منظر کو
جانے کی کوششیں شروع ہو چکی ہیں، یعنی یہ جاننے کی کوشش کی جارہی ہے کہ قرون وسطی سے لے کر نشاۃ ثانیہ
1500- 1300ء ) تک کے سائنسی نظریات کی تاریخ کیا ہے؟ نشاۃ ثانیہ یورپ کی وہ ثقافتی تحریک ہے جس سے
وہاں سائنسی انقلاب بر پا ہوا، اس کا آغاز اٹلی میں چودہویں صدی سے ہوا.نشاۃ ثانیہ کی بنیاد اس وقت پڑی جب
یورپ کے عالموں اور سائنس دانوں نے قدیم یونانی علوم کی تحصیل بڑے شدومد سے شروع کی.اس تمام علمی
خزانے تک جانے کے لئے کا مطالعہ لازمی تھا کیونکہ اس نے ہی تو ارسطو کے سائنسی نظریات اور خیالات کو
صحیح معنوں میں بیان کر کے اس کی اہمیت لوگوں پر آشکارا کی تھی.کی یونانی کتب کی شرحوں سے نشاۃ ثانیہ
کے دیو قامت عالموں کو آئیڈیاز ملے تھے.چودہویں صدی میں پیرس کے محققین نے ارسطو کے نظریہ حرکت ( Theoty of Motion) کو مسترد کیا
تھا.اس کی جگہ ایک نئے تصور جس کا نام اپنی ٹس (Impetus) تھا اور جس کا کسی پروجیکھا ئیل (Projectile)
کے سفر کے دوران ہونا ضروری تھا، نے لے لی.اس کے بعد سائنس داں تھیوری آف انرشیا ( Theory of
Inertia ) پر ریسرچ کرنے لگے جو سترہویں صدی میں مکمل ہوئی.پیرس کے مکتب فکر کے اس سائنسی کام کو اٹلی کی
پیڈ وا یو نیورسٹی میں پندرہویں اور سولہویں صدی میں مزید ترقی ملی.یہ یونیورسٹی میڈیکل ایجو کیشن اور ارسطو کے
سائنسی نظریات کی وجہ سے بہت مشہور تھی.خاص طور پر جس کی شہرت ارسطو کے شارح ہونے کی وجہ سے
تھی، اس کے نظریات (Averroism) کا یہاں بہت اثر ونفوذ تھا جس کا پر تو اطالوی نشاۃ ثانیہ کی سائنس اور
فلاسفی میں صاف صاف نظر آتا ہے.پیڈوا کے محققین نے کی کتابوں اور سائنسی نظریات کو رہنما بنا
کر سائنسی طریقہ (Scientific Method) کی نشو و نما میں اہم حصہ ادا کیا.سائنسی طریقے کی بنیاد پانچ امور پر ہے: 1- کائنات میں کسی مظہر قدرت کا مطالعہ.2.اس مطالعے کی بنیاد
پر مفروضے کی تیاری.3.مفروضے کو مدنظر رکھتے ہوئے پیش گوئی.4.ان پیش گوئیوں کی تجربات کے ذریعے
87
Page 106
آزمائش اور جانچ اور اگر نتائج مختلف ہوں تو ان کی روشنی میں نظریے میں تبدیلی.5.تجربے کو تین چار مرتبہ دہرانا
یہاں تک کہ مفروضے اور مشاہدے میں کوئی تضاد نہ رہے.اس مرحلے میں مفروضہ تھیوری بن جاتا ہے.تھیوری
ایک نظریہ ہے جس میں مشاہدات کی وضاحت اور پیش گوئیاں کی جاتی ہیں.یہ سائنسی انقلاب اسلامی دنیا میں بھی آسکتا تھا مگر علما کے سیاسی اثر اور دگرگوں معاشی اور سیاسی حالات کی وجہ
سے ایسا نہ ہو سکا.: سائنس کا زبردست حمایتی قرون وسطی میں سائنس اور سائنس دانوں کا سب سے بڑا حامی اور طرف دار تھا.امام غزائی نے اپنی
کتاب تهافت الفلاسفة کے ذریعے فلسفے پر جو کاری ضرب لگائی تھی اس کا بڑا انقصان یہ ہوا کہ مسلمان جو کسی وقت
ایک شاندار تہذیب کے مالک اور وارث تھے وہ رفتہ رفتہ فلسفے (سائنس) سے بے زار ہو گئے اور اسلامی سوسائٹی
انحطاط کا شکار ہو گئی.مذہب، فلسفہ اور سائنس کا ہر معاشرے میں اپنا اپنا دائرہ کار ہے.عوام کی فلاح اور بہبود کے
لئے نیز ان کی مادی خوشحالی کے لئے سائنس کا علم بہت ضروری ہے.فلسفہ حقیقت جانے کا یا حقائق سے پردہ
اٹھانے کا نام ہے.ہر انسان کے لئے مذہب بنیادی اہمیت رکھتا ہے، تاریخ انسانی کے مطالعے سے یہ بات معلوم
ہوتی ہے کہ ماضی میں ایسی سوسائٹیاں تھیں جن میں نہ تو سائنس تھی اور نہ فلسفہ ہاں ان میں مذہب ضرور تھا.افلاطون، ارسطو، ابن سینا، ، ڈیکارٹ اور کانٹ کی علمی فضیلت اس بات میں ہے کہ انہوں نے ان مینوں کی
اہمیت کو جانا.عباسی دور حکومت میں جو ابتدائی فلسفی اسلامی دنیا میں پیدا ہوئے وہ سائنس کی اہمیت اور مذہب کی
افادیت سے بخوبی واقف تھے.چنانچہ الکندی، الفارابی، ابن سینا سائنس داں ہو نے کے ساتھ فلسفی اور بچے
اور راسخ العقید و مسلمان بھی تھے.انہوں نے شہرت دوام اس لئے حاصل کی کہ انہوں نے مذہب کے احکام کی اپنے
سائنسی اور فلسفیانہ علم کے احاطے کے اندر رہتے ہوئے تشریح اور تادیل دی.حجتہ الاسلام امام غزالی نے تہافت الفلاسفہ میں فلسفیوں پر کفر کا الزام ان کے ہیں نظریات کی وجہ سے
عائد کیا تھا.نے ان کی کتاب کا رد لکھا اور ان میں التزامات کا جواب تهافت التهافة میں سائنس ، فلسفہ
اور مذہب میں تطبیق پیدا کرتے ہوئے دیا.نے قرآنی آیات کی عقلی و استدلالی تفسیر پیش کرتے ہوئے
مذہب کی طرف جانے والے راستہ کی نشاہدہی کی جو قرآن مجید میں مذکور ہے.نے اس طرح سائنس کا
محافظ ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے سائنسی حقائق کی طرف جانے والے راستے کی رونمائی کی.مثلاً نے کہا
88
Page 107
کر فلسفیوں کو کرشمات کے بارے میں سوال نہیں اٹھانے چاہئیں، ایسا شخص جو ان کے بارے میں شبہات کا اظہار کرتا
ہے سزا کا مستحق ہے.ہاں یہ بھی جانا چاہئے کہ اسلام کا اصل کرشمہ اس بات میں مضمر نہیں کہ سونٹے کو سانپ میں
تبدیل کر دیا جائے بلکہ اسلام کا سب سے بڑا کرشمہ قرآن مجید ہے اور یہ کرشمہ تمام کرشموں پر فوقیت رکھتا ہے.(تهافت التهافة صفحہ312، جلد اول انگریزی ترجمہ Van den Bergh ).پچھلی صدی کے مسلمان علما میں
محمد عبدہ (مصر) اور سید امیر علی (ہندوستان) نے کے اس نظریے سے اتفاق کیا اور اب اسلامی ممالک میں
اس نقطہ نظر کو قبولیت کی سند حاصل ہو چکی ہے.فطرت کے تمام قوانین پر مکمل یقین رکھتا تھا اور کہتا تھا کہ اس دنیا میں ہر چیز مکمل تواتر سے وقوع پذیر
ہوتی ہے جس کو علت اور معلول (Cause and Effect) کو پیش نظر رکھتے ہوئے سمجھا جا سکتا ہے.سائنس کی
طرف جانے کا راستہ مذہب سے شروع ہوتا ہے جس کی بنیاد یقین پر ہے.مادہ پرستوں اور متشکک افراد کے لئے سا
ئنس میں کوئی جاہہ نہیں ہے.دنیا کی ہستی پر اعتماد سے ہی ہماری عقل چیزوں کی علت دریافت کرتی ہے.سائنسی علم
در حقیقت اشیاء کا علم اور ان کے عمل کا نام ہے جو ان
کو پیدا کرتی ہیں.(Scientific knowledge is the knowledge of things with their causes which
produce them.) کا ذکر انسائیکلو پیڈیا میں
انسائیکلو پیڈیا آف ایسٹرونومی اینڈ ایسٹرو فزکس میں پر بطور بیت داں پیش کردہ مضمون کے مطالعے
سے اس موضوع پر مزید دلچسپی رکھنے والے حضرات استفادہ کر سکتے ہیں.http://eaa.ioo.org/index.cfm?action=summary&doc
کہا جاتا ہے کہ بڑے بڑے سائنس دانوں نے جو انقلاب آفریں سائنسی پیش گوئیاں کیں وہ انہوں نے 25
سال کی عمر کو پہنچنے سے پہلے کی تھیں.اس ضمن میں نیوٹن ، آئنسا ئین اور پروفیسر عبد السلام کا نام پیش کیا جا سکتا ہے.کی سائنسی زندگی پر غور سے نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس نے بھی پچیس سال کی عمر کے لگ بھنگ
زبر دست سائنسی کارنامے انجام دئے.بعض لوگ فطرتاً ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی شخصیت کے جو ہر دھیرے
دھیرے کھلتے ہیں ، جوں جوں عمر رسیدہ ہوتا گیا اس کی باکمال شخصیت کے جو ہر کھلتے گئے.علما اور حکما کو
احساس ہوگیا کہ وہ اندھیری رات میں چمکتا چراغ تھا.اس بے مثل چراغ نے اپنی نو پاشیوں سے یورپ کو منور کیا
89
Page 108
مگر عالم اسلام میں چراغ تلے اندھیرا ہی رہا.آئزیک ای موف (Isaac Asimov) جس نے سائنس پر پانچ سو کے قریب کتابیں لکھی ہیں، اس نے
اپنی کتاب بیوگرافیکل انسائیکلو پیڈیا میں 1510 سائنس دانوں کی سوانح عمریاں پیش کی ہیں، ان میں کا ذکر
91 نمبر پر کیا ہے.(38)
90
Page 109
باب پنجم بحیثیت فلسفی و شارح ارسطو
یورپ میں اسلامی فلسفے کا فروغ
اسلامی فلسفے کی اہمیت کا جب یورپ کے اہل علم کو بارہویں صدی میں اندازہ ہوا تو اسلامی اسپین میں ٹولیڈو
( طلیطلہ) کے شہر میں عربی کتابوں کے عبرانی اور لاطینی تراجم کا کام پورے زور شور سے شروع ہو گیا.ان مترجمین میں
مسلمان، عیسائی، یہودی اور اپنینی مترجمین شامل تھے.ان کا سرخیل (ڈین آف ٹرانسلیٹر ز ) جیرارڈ آف
کریمونا (1187-1114 ء ) تھا جس نے فلسفہ و سائنس کے موضوع پر 70 شاہکار عربی کتابوں کے تراجم لاطینی میں
گئے.1180ء میں متعدد ترجمین نے مل کر شیخ الرئیس ابن سینا کے فلسفے کا انسائیکلوپیڈیا ، کتاب الشفاء کا ترجمہ مکمل
کیا.الشفاء نے عہد وسطی میں یورپ کی یونیورسٹیوں میں کئی سو سال تک فلسفہ اور سائنس کی تعلیم پر گہرا اثر چھوڑا.یورپ میں اسلامی فلسفے کے تین دور تھے (1) پہلا دور 1100 ء سے 1250 ء تک جب عربی سے فلسفہ،
الہیات اور سائنس کی کتابوں کے تراجم لاطینی ودیگر یورپی زبانوں میں کئے گئے.چنانچہ قرآن پاک کا پہلا ترجمہ
1143ء میں رابرٹ آف چیسٹر نے کیا.یورپ میں اسلام اور اسلامی سائنس میں دلچسپی پہلی صلیبی جنگ 1095ء
کے بعد شروع ہوئی تھی.(2) دوسرا دور 1250 ء سے 1400 ء تک کا ہے جب اسلام اور سرکار دو عالم ہے کے
خلاف زہریلا پروپیگنڈہ عیسائی پادریوں نے کیا اور مخالفانہ کتا بیں شائع کی گئیں.(3) تیسرا دور 1500-1400ء
کے بعد کا ہے جب صلیبی جنگیں ختم ہوئیں اور یورپ میں اسلامی علوم سے دوبارہ دلچسپی بڑھی.اور یورپ کی متعدد
بڑی لائبریریوں میں عربی کتابوں کے قلمی نسخے اکھٹے کئے جانے لگے.اٹلی میں 1588ء میں گرینڈ ڈیوک آف نوسانی فرڈی نانڈ وکی میڈیسی (Ferdinand de Medici)
نے اپنے مطیع میں عربی کتابوں کی وسیع اشاعت کا کام شروع کر دیا تھا.یورپ کی نشاۃ ثانیہ کے دور( چودہویں تا
91
Page 110
سترہویں صدی) میں پیرس، لیڈن ، روم، آکسفورڈ کی جامعات میں عربی کے پروفیسر تدریس کا کام کر رہے تھے.عیسائی مشنریاں بھی اس معاملے میں کچھ پیچھے نہ تھیں اس لئے اسلام کے بارے میں معلومات اور کتابیں وسیع تعداد
میں لکھی جانے لگیں.1697ء میں پہلے انسائیکلو پیڈیا آف اسلام (Bibliotheque Orientale) پیرس سے
شائع ہوا.پھر سوئٹزر لینڈ کے جو ہان بانگر (1667-1620 Johann Hortinger) نے ابن ابی اصیبعہ کی
کتاب طبقات الاطباء اور ابن ندیم کی کتاب الفهرست کو سامنے رکھ کر ایک کتاب شائع کی.مستشرقین کے
لئے ہسٹری آف اسلامک فلاسفی اینڈ سائنس کے موضوع پر یہ کتاب سب سے مستند ذخیرہ تھی.انگریزی میں
انسائیکلو پیڈیا آف اسلام لیڈن سے 1913ء سے 1938 ء کے دوران چار جلدوں میں شائع کی گئی تھی.سترہویں صدی کا سب سے عظیم مستشرق بلا شبہ ایڈورڈ پوکاک (16-1604 Pocock ) تھا جس نے
فلسفہ کی تعلیم ہائیڈل برگ کے پروفیسر پاسر (Pasor) سے حاصل کی تھی.پوکاک جب شام میں عیسائی مشنری کے
طور پر متعین تھا تو اس نے عربی کتب کے نادر مخطوطات آکسفورڈ یونیورسٹی کے لئے اکھٹے کئے.اس کا ایک اور قابل
ستائش کارنامہ یہ ہے کہ اس نے یورپ میں اسلامی فلسفہ کے فروغ کے لئے دو کتابوں کے ترجمے کئے.پہلی کتاب
مختصر في الدول کالاطینی ترجمہ (Specimen Historiae Arabum) آکسفور؛ سے1663ء میں
منظر عام پر آیا.اس کتاب کو اسلامی فلسفہ کی ہسٹاریو گرانی کی بنیادی اینٹ قرار دیا گیا اور اس کا اثر انیسویں صدی تک
شائع ہونے والی کتابوں میں محسوس کیا جاتا رہا.پوکاک نے اس ترجمہ کے لئے ابن خلکان کی کتاب وفیات الاعیان
شہرستانی کی کتاب الملل والنحل ، ابن الاثیر کی الكامل فى التاريخ ، این حکمون القدوائی ( وفات 1062ء)
کی کتاب الانبیاء والخلفاء موی ابن میمون (1204ء) کی مورے نیوکم (Moreh Nebukim)، امام غزالی کی
احیاء علوم الدین اور عقیدہ سے پورا پورا استفادہ کیا تھا.دوسری کتاب جس کا اس نے انگریزی میں ترجمہ کیا وہ
ابن طفیل کا مشہور فلسفیانہ تاول حی ابن يقظان تھا.یہ ا 167ء میں شائع ہوا.ایڈورڈ پوکاک یورپ میں پہلا مستشرق تھا جس نے عربی زبان کی کتابوں اور خاص طور پر فلسفے کی کتابوں کی
اہمیت کو پہچانا، فلسفے پر اس کی کتاب کا انگریزی ترجمہ 1645ء میں کیا گیا جبکہ اس کے ہم نام بیٹے نے اس کتاب کو
عربی متن اور لاطینی ترجمے کے ساتھ 1671ء میں شائع کیا.ابن طفیل کے ناول کے انگریزی ترجمے کے بعد اس
کے ڈچ اور جرمن تراجم سترھویں اور اٹھارویں صدی میں شائع ہوئے.یوروپین مصنف ڈے نو (Defoe) کے
اول(1719 Robinsan Crusoe) کا ماخذ بھی ابن طفیل کا ناول تھا.اسی زمانے میں پوکاک کے ایک
شاگر د سیموئیل کلارک ( 166-1625 Samuel Clark) نے ایک کتاب لاطینی میں لکھی یعنی ٹریکٹس ڈی
پروسوز یا عربکا ( 1661 Tractatus de Prosodia Arabica).اس میں فلسفے کی تعلیم اور خاص طور پر
92
Page 111
یورپ
کی یو نیورسٹیوں میں عربی زبان کے مطالعے کی اہمیت کو واضح طور پر بیان کیا گیا.ستر ہوئیں اور اٹھارویں صدی
کا زمانہ یورپ میں روشن خیالی (Enlightenment) کا تھا.اس لئے ابن طفیل کے ناول کا دو اور عالموں جارج
کیتھ اور جی ایسویل (George Keith & G.Aswel) نے بھی انگریزی میں ترجمہ کیا.van
فرانس میں لودین (Louvain) یو نیورسٹی کی بنیاد 1425ء میں رکھی گئی.اس یو نیورسٹی میں عربی تعلیم کا آغاز
1542 ء سے ہوا.1893 ء میں یہاں انسٹی ٹیوٹ آف فلاسفی کا قیام عمل میں آیا.اور ہسٹری آف عربک فلاسفی کو
نصاب میں شامل کیا گیا.چھ سال بعد یہ کورس ختم کر دیا گیا.مگر 1965ء میں یہ دوبارہ شروع ہوا 1962ء میں پر
وفیسر سائمن دین ریٹ (Rie
Simon e) سے کہا گیا کہ وہ ابن سینا کی کتاب النفس ، وی اپنی ما
(De Anima) کالاطینی میں تنقیدی اڈیشن تیار کرے.1967ء میں ایک اور کورس شروع کیا گیا جس کا نام
ٹیکسٹ آف عربک فلاسفی تھا.1969ء میں پروفیسر ریٹ نے فلاسفہ کے لئے ایلی مینٹری عربک کورس کا انتظام
کیا.اس کے ساتھ عربک فلاسفی میں بی اے کی ڈگری دینے کا بھی اہتمام کیا گیا.اس سال یو نیورسٹی میں ایک خود
مختار ادارہ سینٹر فار عربک فلاسفی قائم ہوا.اندلس کے فلاسفہ
بارہویں صدی میں عیسائی پادریوں اور علما نے یونانی کتابوں کے
علاوہ مسلمانوں کی درج ذیل کتابوں کے
مطالعے سے فلسفہ کا علم حاصل کیا تھا:
حسین ابن الحلق حسنین جس نے اسلامی دنیا میں سب سے پہلے یونانی کتب کے عربی میں تراجم شروع
گئے.ارسطو کی ذے کو کلو (De Caelo) پر اس کی شرح.قسطا بن لوقا - رساله في الفرق بين الروح والنفس اس کالا مینی ترجمہ ابن داؤد نے کیا تھا.الحق الكندى - رساله فی العقل ، جیرارڈ آف کریمونا نے اس کی تین اور کتابوں کے بھی تراجم کئے.ابونصر الفارابي - رساله في العقل، یہ ترجمہ ابن سینا کی کتابوں کے ساتھ 1508ء میں شائع ہوا
تھا.کتاب فى احصاء العلوم، كتاب في مراتب العلوم
ابوعلی ابن سینا.کتاب الشفاء -
امام غزائی.مقاصد الفلاسفه.عربی کتابوں کے تراجم میں جن یورپی محققین نے حصہ لیا ان میں چار قابل ذکر مترجمین ہرمن دی ڈالمین
Hermann the Dalmatian)، ایڈے لارڈ آف ہاتھ (Adelard of Bath)، ڈینیل آف مورلی
93
f
|
Page 112
(Daniel of Marley) اور گندی سالوس ( Gundisalvus) تھے.(39)
مشرق کے اسلامی فلسفیوں (جیسے الکندی الفارابی، ابن سینا) کی کتابوں اور ان کے فلسفیانہ نظام کے بارے
میں اندلس کے علما خوب واقفیت رکھتے تھے.لیکن اس بات کے تاریخی شواہد بھی موجود ہیں کہ اندلس میں فلسفہ کی تعلیم
پر بعض دفعہ ممانعت بھی لگائی گئی تھی.اسکولوں میں فلسفہ کی تعلیم نصاب میں شامل نہیں ہوئی تھی.ہمارے پاس کوئی
ایسی تاریخی شہادت موجود نہیں جس سے ثابت ہو کہ اندلس میں فلسفے پر یونانی اور لاطینی میں لکھی جانے والی کتابوں
کے تراجم کئے گئے.مشرق کے اسلامی ممالک میں عربی میں جو ترجمے کئے گئے تھے ان پر بھی نظر ثانی کی کوشش نہیں
کی گئی تھی.یہاں فلسفہ کی تعلیم کا انحصار سراسر مشرق کے مسلمان فلسفیوں کی کتابوں ہی پر رہا.فلسفہ کی کتابوں کا مطالعہ
گھروں میں کیا جاتا تھا لیکن قدامت پسند مذہبی علما کی مخالفت کے پیش نظر کھلے عام ان کتابوں پر نقد و نظر یا بحث نہیں
کی جاتی تھی.اندلس میں کھلے بندوں فلسفہ کی تعلیم و تدریس کرنا مصیبت مول لینے کے مترادف تھا.چھوٹے چھوٹے علمی
مسائل پر عوام بھڑک اٹھتے اور دنگا فساد پر آمادہ ہو جاتے تھے.ہر بری قبیلوں کی خانہ جنگی کے زمانہ میں ان لوگوں نے
کتب خانوں کو خوب لوٹا تھا.ابن باجہ جان بچانے کی خاطر ہمیشہ بادشاہوں کی سرپرستی میں رہتا تھا.کے
دادا نے اسے قید خانے سے رہائی دلوائی تھی ورنہ شاید قتل کر دیا جاتا.ابن واہب اشبیلی قرطبہ کا فلسفی تھا اس نے جان
کے خوف سے اپنے قریبی فلسفی دوستوں کو مجالس میں فلسفیانہ مسائل پر بحث کرنے سے روک دیا تھا اور خود بھی اجتر از
کرتا تھا.اگر کسی شخص کے بارے میں علما کو معلوم ہو جاتا کہ وہ فلسفہ کی کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے یا فلسفہ کی طرف اس کا
رجحان ہے تو اس کو ملحد قرار دے کر اسے زدو کوب کیا جاتا نیز اس کے یہاں موجود کتابوں کو نذر آتش کر دیا جاتا تھا.اس کی کئی ایک واضح مثالیں ہیں جیسے ابن مسرہ (931ء) جو اندلس کا سب سے پہلا فلسفی تھا اس کا سماجی بائیکاٹ کیا
گیا.اس کی کتابوں کی اشاعت اور تقسیم پر پابندی لگاؤں گئی تھی.علما فلسفہ کے سخت خلاف تھے اس لئے ان کی
خوشنودی حاصل کرنے کے لئے ابن ابی منصور (1002ء) نے جو اندلس کا طاقتور حاجب اور در پردہ حکمراں تھا حکم
دیا کہ خلیفہ الحلم الثانی کی شاہی لائبریری سے جس میں چار لاکھ کے قریب نایاب کتابیں تھیں منطق ، ہیئت اور علوم
قدیمہ کی کتابوں کو تلف کر دیا جائے.ابن حزم جو قرطبہ کا جامع کمالات محقق اور آزاد خیال ادیب و شاعر تھا اس کو نہ
صرف شہر بدر کیا گیا بلکہ اس کی کتابوں کو خاکستر کر دیا گیا.پھر ایک دور ایسا بھی آیا کہ کی کتابوں کو قرطبہ کے
بازار کے چوک میں آگ کی نذر کیا گیا.ایسا لگتا ہے کہ اس گھٹی ہوئی فضا کے ردعمل کے نتیجہ میں اندلس کے فلسفی فلسفیانہ علوم کے سخت دفاع کرنے
94
Page 113
والے بن گئے کیونکہ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ فلسفے کے ذریعے انسان سچ کی تہ تک پہنچ سکتا ہے.بعض اندلسی فلاسفہ کے
نزدیک فلسفے کی وہی اہمیت اور حقیقت تھی جو دوئی اور الہام کی ہے
بلکہ کچھ نے تو اس کو وحی پر فوقیت دی ہے.ابن حزم
اور ابن طملوس منطق کے بہت بڑے علمبردار تھے.قاضی صاعد اندلسی نے طبقات الامم میں تین محققین کا
خاص طور پر ذکر کیا ہے جو علوم قدیمہ اور فلسفہ میں شغف رکھتے تھے، یعنی ابن النباش الہجائی ، ابوالفضل ابن حسدائے ،
احمد ابن حفصون (المشهور فلسفی ) کی زندگی بطور فلسفی جاننے کے لئے اندلس کے فلاسفہ اور فلسفہ کے وہاں رواج پانے کا پس منظر جانتا
اہم ہے.اس لئے چیدہ چیدہ اندلسی فلسفیوں کے حالات کسی قدر تفصیل سے یہاں پیش کئے جاتے ہیں تا کہ یہ معلوم
ہو سکے کہ اندلس فلسفہ کے میدان میں بے آب و گیاہ صحرا کے مانند نہیں تھا.اسی اندلسی گلستان کی پیداوار تھا
جس کے پھولوں کی معطر جاں خوشبو نے یورپ کو اپنے سحر میں لے رکھا تھا.(1) محمد ابن عبد اللہ ابن مسرہ (931ء ) دسویں صدی کا عظیم فلسفی تھا.اندلس سے اس نے مشرق کے
اسلامی ممالک کا سفر کیا جہاں وہ معتزلہ خیالات اور تصوف سے بہت متاثر ہوا ، خاص طور پر عقیدہ قضا و قدر اور اس
نظریے سے کہ قرآن تخلیق شدہ ہے.جب وہ اندلس واپس آیا تو اس نے ان غیر قدامت پسند نظریات کا پر چار
شروع کیا مگر وہ علما اندلس کی نظروں میں کھٹکنے لگا.ابھی وہ عمر کی تیسویں منزل میں تھا کہ علما نے اسے محمد قرار دے دیا
چنانچہ وہ قرطبہ سے فرار ہو کر شہر کے نزدیک پہاڑوں میں روپوش ہو کر زاہدانہ زندگی گزارنے لگا.اس کے مریدوں کا
ایک حلقہ اس کے گرد جمع ہو گیا جو اس کی طرح زاہد : عابد اور تارک الدنیا بن گئے.اس نے وحدت الوجود (یعنی
کائنات اور خدا ایک ہیں ) کے نظریہ کو اندلس میں فروغ دیا جس سے اسلامی نظریہ تصوف کی بنیاد اندلس میں رکھی
گئی.اس نے دو کتابیں تصنیف کیں جنہیں اس کی زندگی میں ضبط کر لیا گیا اور اس کی رحلت کے بعد کچھ عرصہ وہ
زیر زمین ہی رہیں.حج کے بہانے وہ حجاز گیا مگر عبد الرحمن الثالث کے دور خلافت میں واپس آ گیا.اس کی وفات پر
لوگوں نے اس کو ولی اللہ تسلیم کیا.(2) گیارہویں صدی میں اندلس میں سیاسی طور پر بہت غلفشار تھا.مگر اس کے باجود متعدد علما نے نام پیدا
کیا.سعید ابن فتوح (وفات 1029ء ) ساراگوسا ( سرقسطہ ) کا باشندہ تھا جو حمار کے نام سے بھی معروف تھا.اس
نے خلیفہ عبد الرحمن سوم اور خلیفہ الحکم الثانی کے دور حکومت میں کئی فلسفیانہ کتابیں تصنیف کیں.ان میں ایک کا نام
شجرات الحكمة (The Tree of Knowledge ) تھا جو فلسفے کے تعارف پر ہے.حاجب ابن ابی عامر
نے اس کو زنداں میں ڈال دیا ، رہائی پر وہ پسلی میں آباد ہو گیا.مؤرخ مقری نے اپنی کتاب نفح الطيب میں اس
کا ذکر کیا ہے.95
Page 114
(3) ابن حزم (1064ء ) عروس البلاد قرطبہ میں پیدا ہوا ، جہاں اس کے والد وزیر مملکت کے عہدہ پر فائز
تھے.خلیفہ عبد الرحمن خامس نے ابن حزم کو 1024ء میں اپنا وزیر مقرر کیا لیکن چند ماہ بعد خلیفہ کے قتل ہونے پر ابن
حزم نے سیاست سے کنارہ کشی کر کے تالیف و ترجمہ کا کام شروع کر دیا.اس کی تصانیف کی تعداد چار سو کے قریب
ہے.ان میں طوق الحمامه (فلسفه محبت پر)، جوامع السياسه ، كتاب الاحکام فی اصول
الاحكام الناسخ والمنسوخ ، تواریخ الخلفاء وغیرہ ہیں.اس نے منطق کے موضوع پر ایک کتاب قلم بند
کی جس کا نام التقريب لحد المنطق والمدخل اليہ تھا.یہ کتاب منطق پر ارسطو کی آٹھ کتابوں کے
مجموعے آرگنان (Organon) کا لب لباب تھی اس کتاب میں اس نے فقہ اور لسانیات کی مثالیں وضاحت کے
طور پر پیش کی ہیں.اس نے اپنے ہم عصروں
کو فلسفہ اور منطق
کی صحیح اہمیت کو نہ جانے پر آٹھ آٹھ آ نسور لائے ہیں.اس کے نقطہ نظر کے مطابق مذہب اور فلسفہ میں کوئی تنازع و تضاد نہیں ہے.اس کے نزدیک کسی کی رائے کو
غلط یا صحیح ثابت کرنے کا سب سے اچھا طریقہ منطق ہے بلکہ وہ اپنے قاری کو منطق کی تعلیم حاصل کرنے پر آمادہ کرتا
ہے تا کہ وہ سچائی پر پڑے دبیز پردوں
کو بنا کر اصلی حقیقت کو جان سکے.جب اس نے مراتب العلوم تصنیف کی تو
اس میں بھی انہی خیالات کا اعادہ کیا.وہ کہتا ہے کہ جو لوگ علم کی اہمیت و افادیت کو جانتے ہیں ان کو دوسروں پر منطق
کی اہمیت واضح کرنی چاہئے.وہ پورے زور سے ان بودے الزامات کی تردید کرتا ہے کہ علوم قدیمہ (منطق و فلسفہ )
کی کتابوں کے مطالعہ سے انسان ملحد و بے دین ہو جاتا ہے.اس کے نزدیک اسلام تمام دوسرے مذاہب سے اعلیٰ وارفع دین ہے.اس کا دماغ حد درجہ منطقی تھا.اس کی
کتابوں اور اس کی زندگی کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اسلام کا نہایت جلیل القدر مصنف ، عالم بلکہ فی الواقعہ
سلطان القلم تھا.اس کی زندگی پر اپنینی میں قابل ذکر کتاب کا نام، اے بن حیزم ڈی کارڈووا (Abenhazam
de Cordova by Asin Palacios ہے.اس نے اپنی مشہور زمانہ کتاب الفصل في الملل و
النحل میں خدا اور اس کی صفات پر فلسفہ اور مذہب کے نظریات کا موازنہ پیش کیا ہے.اس کتاب میں اس نے
تقابلی مطالعہ ادیان بھی پیش کیا جس کی بناء پر یہ کتاب اس موضوع پر دنیا کی پہلی کتاب شمار کی جاتی ہے.بقول
سرٹامس آرنلڈ ابن حزم پہلا متفق تھا جس نے نئے اور پرانے عہد نامے کا تنقیدی مطالعہ کیا.(First systematic critical study of Old and New Testament)
كتاب الاخلاق میں اس نے نیک زندگی گزارنے کے طریقے بیان کئے ہیں.مابعد الطبیعات پر
زکریا رازی کی کتاب کو اس نے ہدف تنقید بنایا اور کہا کہ مشرق کے اس فلسفی پر زرتشتی مذہب کے نظریات کا بہت اثر
تھا.ابن حزم عصمت انبیاء کا قائل تھا.وہ نبوت کے معاملے میں مردوزن کی تفریق کا قائل نہیں تھا اور کہتا تھا کہ
96
Page 115
عورتیں بھی مقام نبوت پر فائز ہو سکتی ہیں.اس کا سب سے بڑا انکشاف یہ تھا کہ فلسفہ مذہب کی قیادت میں چلے تو
حقیقت کو پالیتا ہے ورنہ ناکام ہو جاتا ہے.اس نے دہریہ فلاسفہ اور معتزلہ پر کڑی تنقید کی.خود ظاہری عقائد کا پیرو
کا ر تھا یعنی قرآنی آیات کے ظاہری الفاظ و معانی میں کسی تاویل کو گوارانہیں کرتا تھا.(4) ابن فتوح کے ہم عصر عبد الرحمن ابن اسماعیل ابن زید کا لقب اقلیدس تھا.وہ اوائل عمر میں ہی ہجرت کر
کے مشرق کی طرف روانہ ہو گیا جہاں اس کی وفات ہوئی.وہ ایک ممتاز ریاضی داں تھا جس کو منطق پر بھی عبور حاصل
تھا.قاضی صاعد بن احمد اندلسی (1070ء) نے اپنی کتاب طبقات الامم میں اس کا ذکر کیا ہے.(5) ابن الکتانی نے فلسفہ پر کئی رسالے تصنیف کئے جن میں سے ایک کا نام کتاب التحقيق في نقد
كتاب العلم الالهي لمحمد زکریا الطبیب ہے.اس کے شاگر درشید کا نام ابن حزم ہے جس کے مطابق
الکتانی کی کتابیں اعلیٰ درجہ کی اور نہایت مفید تھیں.(6) ابن حزم کا ایک ممتاز ہم عصر ابن جبرائیل (1070 ء ) تھا جو بندرگاہ والے شہر ملاغہ کا باشندہ تھا.اس
نے اپنی شاہکار تصنيف ينبوع الحیات کے ذریعے نوافلاطونی فلسفه (Neo-Platonic
Philosophy ) کا پرچار کیا.اس کی کتاب کا ترجمہ لاطینی میں اسپین کے مشہور عالم اور مترجم گندی سالوی
Gundisalv) نے 1150 ء میں کیا.وہ کہتا ہے کہ انسان اور فرشتے مادہ اور ہئیت سے بنے ہیں.ابن حزم کی
طرح وہ بھی اس نظریہ کا اعادہ کرتا ہے کہ فلسفہ کے مطالعہ سے بچ کی حقیقت کو جانا جاسکتا ہے مگر یہ کام صرف فلسفی ہی
کر سکتا ہے جاہل عوام الناس نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ایسے علم سے نا آشنا ہیں.فلاسفہ کے علم اور مذہبی علما کے علم اور عام
آدمی کے علم میں فرق کے نظام کو ابن باجہ، ابن طفیل ، اور ابن میمون نے بڑی صراحت سے بیان کیا ہے.(7) بارہویں صدی میں فلسفہ کے علم کو اندلس میں چار چاند لگے.ابو بکر محمد بن یکی ابن باجہ (1138ء)
طب ، منطق اور فلسفہ میں مشاق تھا.اس نے مذہب اور فلسفہ میں فرق کو واضح طور پر بیان کیا.ابن طفیل کے مطابق
ابن باجہ کی نظر عمیق اور اس کے خیالات بہت گہرے تھے.اس نے الفارابی، ابن سینا اور الغزائی سے زیادہ فوقیت
حاصل کی.اس بات سے ابن خلدون بھی اتفاق کرتا تھا اور اسے اسلام کے ممتاز ترین فلاسفہ میں شمار کرتا تھا.ابن باجہ کی پیدائش ساراگوسا ( سرقسطہ ) میں ہوئی.انتظامی امور میں وہ اس قدر صائب الرائے تھا کہ سرقسطہ
کے گورنر نے اسے اپنا وزیر بنا لیا تھا.مگر جب آراگان کے الفانسو اول نے شہر پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا تو اس نے
ذلت کی زندگی گزارنے پر جلاوطن ہونے کو ترجیح دی.پہلے وہ ویلنسیا گیا، پھر اشبیلیہ، وہاں سے غرناطہ اور بالآخر فیض
( مراقش) میں مستقل سکونت اختیار کرلی.آزاد خیالی کی وجہ سے علما اسے کافر کہتے تھے.اس شہر میں اس کے دشمنوں
97
Page 116
نے اس کو ہر پلا دیا جس کی وجہ شاید اس کے غیر مذہبی نظریات تھے.اس نے بہت سارے علوم میں تربیت پائی تھی
اس لئے اس نے جملہ مضامین پر قلم اٹھایا جیسے طب موسیقی ، ریاضی، ہیئت اور فلسفہ.اس نے نظمیں بھی کہیں جن کو
موشا کہتے تھے.تاہم اس کی لازوال شہرت کا سبب فلسفہ ہے.اس کے شاگردوں میں سے ابن طفیل ، اور
ابن میمون نے جہانگیر شہرت حاصل کی.اس نے منطق اور مابعد الطبیعیات پر 22 کتابیں لکھیں ، ان کتب میں سے
معدودے چند دستیاب ہیں:.شرح كتاب السماع الطبيعي كتاب اتصال العقل بالانسان كتاب
النفس.مجموعه في الفلسفة والطب والطبيعيات - فصول فى السياسة المدنيته اس نے
ارسطو کی چار کتابوں کی شرحیں اور الفارابی کی منطق کی کتابوں کی تعالیق بھی لکھی ہیں.علم سیاست پر اس کی ذی اثر کتاب کا نام تدبیر المتوحد ہے جس کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ
یونانی اور مسلمان فلسفیوں جیسے افلاطون، ارسطو، جالینوس الفارابی، ابن سینا کے نظام فلسفہ سے پوری واقفیت رکھتا
تھا.وہ اس کتاب میں ان فلسفیوں کے نظریات کا بار بار حوالے دیتا ہے.کتاب سے اس کے اپنے نظام فلسفہ کی
جھلک بھی نظر آتی ہے جس کے مطابق خلوت گزیں انسان خوشی اور کمال کی انتہا تک پہنچ سکتا ہے بشرطیکہ اس کی زندگی
فطرت سے مطابقت رکھتی ہو.گوشہ نشیں کو یہ اوج کمال دولت، اثر رسوخ عزت اور نیکیوں سے حاصل نہیں ہوتا بلکہ
اس وقت حاصل ہوتا ہے جب انسان دنیا کو ترک کر کے زاہدانہ زندگی اختیار کرتا ہے.الفارابی کے نزدیک یہ اوج
کمال انسانی معاشرہ میں رہنے (یعنی مدینہ فاضلہ ) سے حاصل ہوتا ہے جبکہ ابن باجہ کے نزدیک اس کے حصول کا
ذریعہ تدبیر الانسان المتوحد ہے تا کہ وہ سب سے افضل وجود بن جائے.کتاب کے شروع میں ابن باجہ لفظ تدبیر کے معنی بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس کے ایک معنی کسی خاص
مقصد کی خاطر مختلف اشیاء کو ترتیب دینا ہے.اس لئے خدا کو کائنات کا مدبر (حکمراں ) کہا جاتا ہے.وہ کہتا ہے کہ
تمام اشیاء یا تو مادی ہیں یا غیر مادی.مادی اشیاء کی لمبائی، چوڑائی اور گہرائی ہوتی ہے جبکہ غیر مادی اشیاء میں ایسے
اوصاف ہوتے ہیں جیسے شرافت علم نیز دو تمام تصورات ( concepts) جو عقل سے بیان کئے جاسکتے ہیں.پھر
روحانی اجسام کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ مادہ صورت کے بغیر نہیں رہ سکتا جبکہ صورت کا مادے کے بغیر وجود ہو سکتا
ہے.صورت کی بھی کئی صورتیں ہیں جیسے مادی صورت ، آفاقی صورت ، روحانی صورت اور آخری عقلی صورت ( صورة
عقلیہ ) جو سب سے افضل ہے.انسان میں سب سے اچھی صفت ( قوۃ النفس) عقل کی ہے جس کے ذریعے انسان
علم اور حقیقی خوشی حاصل کرتا ہے.جب عقل انسانی کا عقل فعال کے ساتھ اور عقل فعال کیا عقل الکلی (یعنی خدا) کے
ساتھ اتصال ہوتا ہے، تب صحیح خوشی حاصل ہوتی ہے.اس علم اور خدا کی معرفت اور شناخت کے بغیر خوشی ممکن نہیں.گوشہ نشیں اس مقصد کو حاصل کر سکتا ہے.(شریعت میں محقل فعال سے مراد جبریل علیہ السلام ہیں ).98
Page 117
ابن باجہ کہتا تھا کہ بعد از مرگ وہی ارواح باقی رہیں گی جنہوں نے یہاں عقل والہام ہر دو سے توانائی حاصل
کی ہوگی ، باقی فنا ہو جائیں گی.حصول مسرت کا واحد راستہ یہ ہے کہ انسان
علم و حکماء سے تعلق رکھے، محبت کو اوڑھنا
بچھونا اور وصال خدا کو جو کمال حیات سے مقصود حیات بنالے.(8) گوشہ نشیں انسان کے تصور کو ابو بکر ابن طفیل (1110-1185ء) نے اپنے زبر دست ناول 'حی
ابن يقظان میں باکمال طریقہ بیان کیا ہے.ابن طفیل کی پیدائش گاڈ کس ( Gaudix) میں ہوئی.کچھ عرصہ کے
لئے وہ غرناطہ میں طبیب رہا.اس کو ہیئت ، ریاضی، شاعری اور فلسفہ پر مکمل عبور حاصل تھا.کیا اس نے ابن باجہ کے
سامنے زانوئے تلمذ تہ کیا ؟ اس بارے میں مصدقہ اطلاع نہیں ہے.خوش قسمتی سے اندلس میں اس وقت حکمران
وقت فلسفہ کی تعلیم وتبلیغ کو اچھا سمجھتے تھے.ابن طفیل الموحد حکمراں ابو یعقوب یوسف (1163-1184ء) کا شاہی
طبیب اور وزیر رہا.سلطان نے ابن طفیل کو اجازت دی کہ وہ اپنے ارد گر دردشن خیال فلسفیوں کا طبقہ پیدا کرے.چنانچہ اس دور کے عظیم محقق بشمول اس کے حلقہ تلامذہ میں نظر آتے ہیں.اسی نے کو ارسطو کی کتابوں
کی شرحیں لکھنے پر مامور کیا تھا.اس کے قلم سے تین اہم کتابیں منصہ شہود پر آئیں، اسرار الحكمة الاشراقيه (حي بن يقظان)،
رساله في النفس ، كتاب في البقع المسكونه وغير المسكونہ.اس نے متحدو نظمیں رقم کیں.اس کی
شہرت کا مدار اس کے ناول حی ابن يقظان پر ہے جو ادب عالیہ میں شمار کیا جاتا ہے.اس ناول میں دو بڑی
چابکدستی سے انسان کے ارتقاء کے مراحل بیان کرتا ہے پیدائش سے بچپن تک، پھر جوانی اور اس کے بعد بڑھاپا.اس کی زبان بہت سہل اور نہایت عمدہ ہے.شاید اسی وجہ سے یہ کتاب اندلس کی عوامی کتابوں میں شمار ہوئی.تیرھویں
صدی میں روشن خیال مصری طبیب ابن النفیس (1288ء) نے اس کتاب کے موضوع کو مد نظر رکھ کے رسالہ
الكاملية في سيرة النبوية لکھی.دونوں کتابوں میں بہت ساری باتیں مشابہت رکھتی ہیں.ابن طفیل کی
کتاب کو بنیاد بنا کر یورپ کے مصنف ڈینیل نے ن ( 1731-1660ء Daniel Defoe) نے کتاب رابنسن
گروسو Robinson Cruso ) زیب قرطاس کی.ابن طفیل کے فلسفے کا ماحصل یہ ہے کہ انسان کی سب سے بڑی لذت مشاہد ہ ذات ہے جو عبادت سے حاصل
ہوتی ہے.انسانی عقل در اصل عقل کل کا ایک جلوہ ہے جو وہاں سے ٹوٹ کر انسانی بدن میں جلوہ گر ہوا.اور فنا کے
بعد پھر اپنے مرکز کی طرف لوٹ جائے گا.الفارابی کا یہ خیال کہ نبوت کیسی ہے، غلط ہے.تنہا عقل اور کشف حقیقت
تک نہیں پہنچ سکتے ، انہیں ایک دوسرے کا معاون ہونا چاہئے.یہ درست ہے کہ بعض حقائق تک رسائی صرف کشف
سے ہو سکتی ہے لیکن کشف زندگی کے تمام اسرار بے حجاب نہیں کرتا، اسے قدم قدم پر عقل کی ضرورت ہوتی ہے.99
Page 118
کائنات کی ہر چیز دوسروں کے لئے ہے.درخت اپنا پھل خود نہیں کھاتے، دریا اپنا پانی خود نہیں پیتے.پس وہی
زندگی نظام کائنات کے مطابق ہو سکتی جو دوسروں کے لئے ہو.(40)
(9) (1198ء) کی فلسفیانہ کتابوں نے یورپ کے علمی حلقوں اور دانشوروں پر تیرہویں سے
سولہویں صدی تک گہرا اثر چھوڑا.اس نے فلسفہ اور طب میں نہایت اعلیٰ پایہ کی کتا بیں تصنیف کیں.یورپ میں اس
کی شہرت کو ارسطو کی کتابوں کی فقید المثال شرحوں ) کتاب النفس، كتاب العقل ، كتاب الحيوان ، کتاب
الاخلاق ) کے لکھنے کی وجہ سے چار چاند لگے.ارسطو کو معلم اول اور الفارابی کو معلم ثانی کہا گیا ہے جبکہ کو
شارح ارسطو (The Commentator) کے نام سے یاد کیا جاتا رہا.دانتے (Dante) نے اس کو
"Avcrrois chel gran comentofeo" کے لقب سے نوازا تھا.کسی کتاب کی شرح لکھنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہوتا.جارج سارٹن نے کہا ہے کہ شرح لکھنا عہد وسطی میں
در اصل
کسی موضوع پر اپنے خیالات کی اشاعت کرنا ہوتا تھا.مثلاً ارسطو کی کسی کتاب پر شرح لکھنے کا مطلب اس کی
تحریروں کو بنیاد بنا کر فلسفیانہ یا سائنسی انسائیکلو پیڈیا تیار کرنا ہوتا تھا.ارسطو کی کتابوں کے ناموں کے مطابق دنیا علوم
کی تقسیم کرتی چلی آرہی ہے.نے بھی شر میں لکھتے ہوئے اس
کی کتابوں کی نام تبدیل نہیں کئے.نے فلسفہ پر 38 مایہ ناز کتابیں ( مثلا جواهر الكون ، المسائل المنطقيه، مبادى
الفلسفه، مقاله في الزمان، مقاله في علم النفس، كتاب فی اتصال العقل ) قلم بند کیں.وہ ارسطو کو
غیر معمولی قابلیت کا انسان تسلیم کرتا تھا جس نے صداقت اور حقیقت کو پا لیا تھا.اسلامی دنیا میں اس وقت ارسطو کو کوئی
خاص وقعت نہیں دی جاتی تھی مگر نے ارسطو ازم کو اس تاریک دور میں زندگی بخشی.اندلس میں اس وقت
کھلے عام فلسفہ کے موضوعات پر بحث نہیں کی جاتی تھی مگر کی خوش قسمتی کہ اس وقت الموحد حکمرانوں کا دور
حکومت تھا.نیز اتنی مہارت حاصل کر چکا تھا کہ وہ فلسفے کے رموز و اسرار سے بخوبی واقف تھا.کے فلسفے کا ماحصل یہ ہے: کائنات محض عدم سے پیدا نہیں ہوئی بلکہ اس دخان (کیسی مادے) سے
نمودار ہوئی جو قبل از آفرینش فضا میں موجود تھا ( قرآن حکیم 41:10 ).مادہ قدیم ہے اور اس کی بدلتی ہوئی صورتیں
حادث ہیں.انسانی افعال ارادہ سے تخلیق ہوتے ہیں اور ارادہ ماحول کی تخلیق ہے.پس انسان مجبور محض ہے اور
کائنات میں سب کچھ مشیت خداوندی سے ہو رہا ہے.افلاک ازلی ہیں ، حرکت افلاک کا خالق خدا ہے.ارواح
فانی ہیں.اسلام کی وہی تعبیر و تشریح ٹھیک ہے جو ارسطو کے نشہ سے مطابقت رکھتی ہے.کشف دو جدان محض خیالی
چیزیں ہیں، اصل حقیقت فکر ہے جس سے حقائق کا ادراک ہوتا ہے.انتہائی سعادت عقل کل سے اتصال ہے.100
Page 119
اجرام فلکی (ستارے ) مادی نہیں بلکہ نفوس وارواح ہیں.روح کیا ہے؟ کا پختہ یقین تھا کہ روح کا تعلق جسم سے اسی طرح ہے جس طرح صورت کا مادہ سے
ہے.ابن سینا کا نظر یہ تھا کہ دنیا میں متعدد لافانی روحیں ہیں ، اس سے متفق نہیں تھا.اس کے نزدیک روح
سے ہی جسم مکمل ہوتا ہے، انسانی روح کوئی الگ چیز نہیں، بلکہ جسم کا ضمیمہ ہے.کے نزدیک کائنات ابد سے حرکت میں ہے اور اس کا ایک دوامی محرک ہے، جس کا نام خدا ہے.ذہن کے ماسوا مادہ (Matter) اور صورت (Form) الگ الگ نہیں ہو سکتے.مادہ ہمیشہ حرکت میں رہتا ہے جبکہ
عقل غیر متحرک ہے.روح تمام انسانوں میں ایک جیسی پائی جاتی ہے، لیکن یہ جسموں میں الگ الگ بستی ہے.روح
اور جسم کا وہی رشتہ ہے جو مادہ اور صورت (Matter & Form) کا ہے.ان جیسے مسائل میں اس نے ارسطو کی
تقلید کی.فلسفے کا دفاع سے قبل مشرق میں الکندی ، الفارابی ، ابن سینا اور مغرب میں ابن حزم ، ابن باجہ، ابن
طفیل کر چکے تھے مگر اس قدر یقین اور اتنی وضاحت سے نہیں.کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے
فلسفے کا دفاع یقین کامل اور وضاحت سے کیا.اس کے نزدیک فلسفہ دین کا دوست اور رضاعی بہن ہے.فلسفہ اور
شریعت میں کوئی تضاد نہیں اور نہ یہ ایک دوسرے کو رد کرتے ہیں.جس طرح شریعت کے ذریعہ حقیقت وصداقت کو
پاناممکن ہے اسی طرح فلسفہ سے بھی حقیقت کی تہ تک پہنچا جا سکتا ہے.این رشد نے ان خیالات کا اظہار فصل المقال و تهافت التهافة اور دوسری کتابوں میں کیا ہے.اس
نے مزید لکھا کہ : " فلسفہ محض غور و فکر اور اشیاء کے مطالعے کا نام ہے.مذہب اسلام چونکہ سچا ہے اس لئے یہ ہمیں
ایسے علم (فلسفہ) کے حاصل کرنے کے بارے میں ترغیب دیتا ہے (لعلکم تنظرون ) جو صداقت و حقیقت کی
طرف رہ نمائی کرتا ہے.ہمارے پاک صحیفہ (قرآن) نے جو ہمیں سکھلایا اس میں کوئی تضاد نہیں ہو سکتا کیونکہ سچائی
سچائی کے خلاف نہیں ہو سکتی بلکہ اس سے مطابقت رکھتی اور اس پر گواہ بنتی ہے.اگر قرآن کی آیات کے معانی میں اور
برہانی نتائج میں تضاد ہو تو ان کی تشریح تمشیری کرنی چاہئے:
"Truth does not oppose truth but accords with it and bears witness to it.If
there is conflict in the meaning of the scripture with demonstrative
conclusions, it must be interpreted allegorically."
فصل المقال' کا آغاز اس دعوئی سے شروع ہوتا ہے کہ شریعت کے جاننے کے لئے فلسفے کی تعلیم ضروری
101
Page 120
ہے اور فلسفہ میں کوئی ایسی چیز نہیں جو شریعت کے قوانین سے تناقض و تضاد رکھتی ہو.شریعت کا مطالعہ تمام لوگوں کے
لئے ممکن ہے اور اس کا بڑا مقصد نیک اعمال بجالاتا ہے، جبکہ فلسفہ صرف چند لوگوں کے لئے ہے جو دلائل دے سکتے
ہوں اور سمجھ سکتے ہوں.عوام الناس جن کی اکثریت سادہ لوح ہوتی ہے ان کے لئے مذہبی عقائد پر صرف ایمان لاتا
ہی واجب ہے.دنیا میں تین قسم کے انسان پائے جاتے جو تین قسم کے دلائل سے قائل ہوتے ہیں: (1) مٹھی بھر
لوگ البر هانیون ) جو برہائی دلائل (Demonstrative) سمجھ سکتے ہیں، ان میں علما و فلاسفہ شامل ہیں جن کا
شمار سوسائی کے طبقہ اشرافیہ (Elite Class) میں ہے.استدلال بر ہانی سے یقینی نتائج پر پہنچا جا سکتا ہے.(2) جمہور کی تقلیل تعداد ( الجدلیون) جو صرف جدلی دلائل (Dialectical) سمجھ سکتی ہے.اس میں علم کلام کے
ماہر (متكلمون ) ، علمائے سوء اور اہل مناظرہ شامل ہیں.استدلال جدلیاتی سے ہم حسن نیت سے ایسے نتائج پر پہنچتے
ہیں جو یقینی نہیں ہوتے.(3) عوام الناس ( الجمهور ) جو انبیاء ، اہل سیاست اور دینی علما کے خطابی دلائل
(Rhetoric) ہی سمجھ سکتے ہیں.استدلال خطیبانہ سے ہم ایسے نتائج پر پہنچتے ہیں جو حقیقت کے قریب ہوتے ہیں.کا کہنا تھا کہ " جن لوگوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے صرف وہی فلسفے کا مطالعہ کریں کیونکہ ایسے ہی
لوگ فلسفیانہ نظریات کو سمجھ سکتے ہیں.ایسے لوگوں کو اپنی فلسفیانہ آراء جمہور، ماہرین علم کلام اور علماے دین کو نہیں بتانی
چاہئیں.جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ فلسفے کا مطالعہ اور اس کا استعمال بدعت ہے کیونکہ اوائل اسلام میں اس کا رواج
نہ تھا تو میں کہتا ہوں پھر ان کو فقہ میں قیاس (Logical Deduction) کے استعمال کو بھی بدعت قرار دینا چاہئے".کے نزدیک شریعت اور فلسفہ ایک ہی مرتبہ پر ہیں.اس نے اس بات پر زور دیا کہ شریعت کی طرح
فلسفہ بھی اس طبعی دنیا اور مابعد الطبعیاتی دنیا کی حقیقت کو جانے کا مصدقہ طریقہ ہے.ایسے نظریات کی بناء پر ابن
رشد جمہور کی آنکھوں میں کھٹکتا رہا.یہاں تک کہ تیرہویں صدی میں یورپ میں اہل نصاری بھی اس کے گہرے
نظریات کی تہ تک نہ پہنچ سکے.اہل نصاری کے نزدیک رشدی تحریک (Averroism) کا نصب العین یہ ثابت کرنا
تھا کہ فلسفہ تو سچا ہے اور مذہب جھوٹا ہے.اس کے باوجود نے یورپ میں ارسطو کی کتابوں کی تفاسیر کے
ذریعے متکلمانہ سیسی کے فروغ میں زبردست کردار ادا کیا.اگر چہ عالم اسلام میں اس کے پیروکار معدودے چند تھے
مگر یورپ طریقہ (Scholasticism) میں بڑے بڑے جید محقق (Galaxy of Scholars) اس کے
معتقد، مقلد اور ناقد تھے.چنانچہ اس کی تلاشخیص اور شروح کے عبرانی اور لاطینی ترجمے مومز ابن طبون ( Moses
1283,Ben Tibbon)، مائیکل اسکاٹ (1232 ,Michael Scott) ہیر سن دی جرمن ( Herman
the German ) ، لیوی بن جرسان (1344 Levi Ben Gerson ) جیسے اعلیٰ پایے کے محققین نے کئے.کی وفات کے صرف 19 سال بعد مائیکل اسکاٹ نے 1217ء میں ٹولیڈ و ( طلیطلہ ) میں سب سے پہلے
102
Page 121
اس کی شرحوں کے تراجم لاطینی میں کئے تھے.موسیٰ ابن میمون نے اپنی شاہکار کتاب دلالۃ الحیرین میں اس کی
کتابوں سے خوشہ چینی کی.راجر بیکن اور ٹامس ایکوئے ناس اس کے فلسفے سے بہت متاثر تھے.ایکوئے ناس نے
اپنی کتاب کوکس چنز ( Questions) میں خدا کے علم کی نوعیت پر کے نظریات کے حوالے بار بار دئے
ہیں.فرانسسکن (Franciscan) فرقہ کے لوگ اس کے فلسفے کا بیانگ دہل پر چار کیا کرتے تھے.رشدی تحریک
یورپ میں سولہویں صدی تک پنپتی رہی.افسوس اس بات کا ہے کہ بعض فضلا نے اس کے نظریات میں سے اسلامی
عصر کو نکال کر پیش کیا.(10) ابن طملوس (1225ء) نے ابن حزم کے ڈیڑھ سو سال بعد اندلس میں شہرت حاصل کی.وہ اپنے ہم
عصروں کی علمی قابلیت پر آنسو بہاتا ہے کہ ان کو منطق کی اہمیت کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے.اس کی پیدائش ویلنسیا
(Valencia) میں ہوئی.بچپن میں اس نے روایتی مضامین کی تعلیم حاصل کی.عنفوان شباب میں وہ قرطبہ منتقل ہوا
اور شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے کے سامنے زانوئے تلمذ تہ کیا.اس نے اپنی تصنیف کتاب
المدخل لصنعة المنطق (Art of Logic ) میں اندلس میں منطق کے مضمون کی تعلیم کی صورت حال بیان
کی.اس کی اہمیت بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ کس طرح اس نے منطق
کی تعلیم کسی استاد کے بغیر حاصل کی کیونکہ اس
کے ہم عصر دانشوروں کا طبقہ منطق کی تحصیل علم سے تغافل شعار بلکہ اس کے خلاف اور متعصبانہ رائے رکھتا تھا.وہ کہتا
ہے کہ علم عروض، علم انشا فمن تقریر علم لغت ، صرف ونحو طبعیات، جیومیٹری، ریاضی، ہیئت، موسیقی کے علوم کی تحصیل پر
یہاں بہت زور دیا جاتا ہے.ان علوم پر قدما ء بہت لکھ چکے ہیں اس لئے مزید لکھنا ہرانے کے مترادف ہوگا.البتہ دو مضامین ایسے ضروری ہیں جن پر لکھنا مناسب ہو گا یعنی منطق اور مابعد الطبعیات.مابعد الطبعیات کا
جو تعلق مذہب سے ہے اس بناء پر اس پر قدرے لکھا گیا مگر منطق کے ساتھ بہت غفلت برتی گئی.ابن طملوس کہتا ہے
کہ اس غفلت کی وجہ یہ تھی کہ لوگ اس کو بے سود گردانتے تھے اور ڈرتے تھے کہ کہیں ان پر الحاد کا التزام نہ لگا دیا
جائے.وہ ان علما پر تعجب کا اظہار کرتا ہے جو حقائق کو زبانی یاد کر لیتے ہیں خاص طور پر مالکی مسلک کے پیروکار.اس
صورت حال کے پیش نظر اس نے منطق کا مطالعہ ضروری جانا اگر چہ اس کو ماسوا امام غزائی کی کتابوں کے اس موضوع
پر کوئی کتاب میسر نہ ہوئی.امام الغزائی کی کتابوں کو اس نے پورے ذوق و شوق سے پڑھا.علاوہ ازیں الفارابی کی
کتابیں بھی بہت مفید ثابت ہوئیں.منطق کے علاوہ اس کے تجربے کا نچوڑ یہ ہے کہ فلسفہ انسانی عقیدہ کے لئے سود
مند ہے، یہ وحی والہام سے متصادم نہیں ہے.دلچسپ بات یہ ہے کہ ابن طملوس نے اپنے قریبی ہم عصر کی فلسفہ اور منطق کی کتابوں کا بالکل
ذکر نہیں کیا اور نہ ہی دیگر اندلسی فلاسفہ کی کتابوں کا.ممکن ہے کہ اس کی زندگی میں کی کتا میں بازار میں
103
Page 122
دستیاب نہ ہوں؟ یا ممکن ہے کہ اس نے اپنے استاد کا ذکر جان بوجھ کر نہیں کیا تا کہ اندلس میں منطق کے علم کو احیاء ثانی
عطا کرنے کا پورا اعزاز اس کومل جائے.الموحد حکمراں ابو یوسف کے دور میں کو شہر بدر کیا گیا تھا اور اس کی
کتابیں ضبط کی گئی تھیں، ممکن ہے کہ ابن طملوس کی زندگی میں یہ منفی رجحان برقرار رہا ہو کہ چونکہ زیر عتاب
ہے اس لئے اس سے اجتناب مناسب ہے.سے فلسفہ سے تعلق کی بناء پر جو سلوک کیا گیا اس سے اندلس
میں فلسفہ کی تعلیم حاصل کرنے میں مضمر خطرات واندیشوں کا اندازہ ہوتا ہے.رشدی تحریک
بارہویں صدی کے آخر میں یورپ میں فلسفہ کی ایک تحریک کا جسے رشدی تحریک (Averroism ) کا نام دیا
گیا تھا، آغاز ہوا.اس تحریک کی بنیاد کے تشریح کردہ ارسطو کے مزعومہ نظریات پر تھی.اس میں دو بڑے
فلسفیوں نے خاص طور پر حصہ لیا، دیگر آف برابانت (Siger of Brabant ) اور ٹامس ایکوئے ناس
(Thomas Acquinas).یگر فرانسکن فرقہ کا پیروکار، لبرل گروپ کا لیڈر اور کا زبردست حامی تھا.ٹامس ڈومینیکن فرقہ کا
پیروکار، کنز رو بیو گروپ کا لیڈر اور کا شدید مخالف تھا.رشدی تحریک کے عقائد یا نظریات درج ذیل تھے جو کی ارسطو کی کتابوں کی شرحوں سے محققین نے اخذ کئے تھے.بدقسمتی سے نے جو کچھ لکھا تھا اسے غلط
طور پر سمجھا گیا.سر ٹامس آرنلڈ اس بات سے اتفاق کرتے ہوئے کہتا ہے:
In default of accurate study of what Averroes actually wrote and
taught it was inevitable that the Church should condemn Ibn Rushd.لوگوں نے بہت سارے مفروضے خود اپنی طرف سے گڑھ لئے اور ان کو کی طرف منسوب کر دیا.یہ دنیا
لاقانی اور غیر دائی ہے.روح کی دو قسمیں ہیں ، ایک انفرادی دوسری خدائی.انفرادی روح لافانی نہیں ہے.تمام
بنی نوع انسان میں ایک ہی غیر دائمی عقل اور روح موجود ہے، اس کا نام (Monopsychism) ہے.مُردوں کا
جسمانی شکل میں دوبارہ زندہ ہونا (معاد) ممکن نہیں.مذکورہ بالا مفروضات سے مشابہ 19 مفروضات کو کیتھولک چرچ نے پیرس یونیورسٹی میں پوپ کی اجازت
سے پہلی بار 1270 ء اور دوسری بار 1277ء میں مزید 219 مفروضات کو لائق تعزیر قرار دے کر ان کی تشہیر اور تبلیغ پر
مذہبی پابندی لگائی.یہ ایک قسم کا پاپائے روم کی مذہبی عدالت کا فرمان (Papal Inquisition ) تھا.حیرانی کی
104
Page 123
بات یہ ہے کہ ایک سو سال بعد ای پیرس یونیورسٹی میں پروفیسروں سے کہا گیا کہ وہ قسم کھا کر عہد کریں کہ وہ ارسطو
کے صرف انہی نظریات کی تعلیم دیں گے جن کی تشریح نے کی ہو (42)
میگر آف برابانٹ (1284ء-1240ء ) ساربون یونیورسٹی (فرانس) میں رشدی تحریک کا بانی اور سب سے
بڑا حامی تھا.اس کم بخت نے بہت سے بے ہودہ نظریات سے منسوب کر دئے.مثلا فلسفہ سچا ہے اور مذہب
باطل.ہوتا یہ تھا کہ وہ عیسائیت کے کسی عقیدے پر بحث کے دوران اپنے دعوئی کے حق میں ارسطو کو بطور سند پیش کرتا
اور جب اس کی تاویل اور تشریح میں کوئی رکاوٹ لاحق ہوتی تو کی شرح میں سے حوالے مسخ کر کے پیش
کر دیتا.چرچ والے اس کو ریڈیکل (انتہا پسند ) گردانتے تھے.اس نے عقل اور مذہب کے درمیان مفاہمت پیدا
کرنے میں حتی الامکان کوشش کی.سیگر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ دو ہری سچائی (Double Truth) کی
تعلیم دیتا تھا یعنی ایک چیز عقل کے مطابق ٹھیک ہو سکتی ہے مگر اس کا بالکل متضاد مذہب میں سچا ہو سکتا ہے.اسی
نظریے کی وجہ سے اسے یونیورسٹی سے خارج کر دیا گیا اور اس کے مانے والوں کو نشانہ ستم بنایا گیا.رشدی تحریک کا
ایک اور حامی ڈنمارک کا فلسفی بو نھیں آف ڈاسیا ( 1290-1240 Boethius of Dacia) تھا جو یونیورسٹی
سوربون (فرانس) میں فعال تھا.اس نے لاطینی میں متعدد کتا میں قلم بند کیں جو چھ جلدوں میں کو پر بیگن سے شائع
ہوئی ہیں.رشدی تحریک پر جب 1277ء میں پابندی لگادی گئی تو وہ پیرس سے غائب ہو گیا.رشدی تحریک کے حامیوں میں سسلی کے بادشاہ فریڈرک دوم کا نام بھی آتا ہے جس کو اپنے ان عقائد کی وجہ
سے چرچ سے خارج کر دیا گیا تھا.راجر بیکن بھی اس کا حامی تھا ، اطالوی مصور پینٹر لینارڈو ڈاونچی (Leonardo
Da Vinci) بھی کے عقائد سے متفق تھا.بعض اطالوی مصوروں نے تو کو اپنی پینٹنگ میں دجال
کی صورت میں پیش کیا تھا.چرچ والوں نے 1512ء میں اس تحریک کے پیروکاروں
کو ملحد و بے دین اور تحریک کو لعنتی
قرار دے دیا.ٹامس گولڈ اسٹین نے اس تحریک کے بارے میں لکھا ہے:
Averroism served as a rallying point for a radical brand of scientific
rationalism for two to three centuries.(43)
نامس اسکوئے ناس (1274-1225 Thomas Acquinas) نیپلز یونیورسٹی (اٹلی) کا کیتھولک فلسفی
اور مذہبی عالم تھا.یاد رہے کہ یو نیورسٹی آف پیزوا، پیرس اور بولونیا رشدی تحریک کا گڑھ ( hot bed of
Averroism ) ہوا کرتی تھیں.ٹامس کا علمی شاہر کار ساتھیولوجی کا (Summa Theologica) ہے.اس کی
105
Page 124
علمیت اور رتبے کے پیش نظر چرچ نے اسے انجیلک ڈاکٹر (Angelic Doctor) کے لقب سے نوازا تھا.1323 ء میں اسے سینٹ قرار دیا گیا.اگر بارہویں صدی کا افضل ترین ارسطو طالیسی تھا تو تیرہویں صدی
کا سب سے بڑا ارسطو طالیسی ٹامس ایکوئے ناس تھا.اور ٹامس دونوں نے ارسطو کی کتابوں کی شرحیں
لکھیں.دونوں نے عیسائی اور اسلامی اعتقادات کو مابعد الطبعیاتی نظریات سے ہم آہنگ کرنے کی کوشش کی.دونوں اپنے دعووں کے حق میں اپنی مذہبی کتابوں قرآن اور بائیل سے آیات پیش کرتے تھے.دونوں سنجیدہ مسائل
میں دلچسپی رکھتے تھے جیسے عقل اور مذہب، انسانی آزادی، خدا کی ہستی کا اثبات، خدا کی صفات تخلیق کائنات ، روح
کا لا فانی ہونا عقل اور الہام، روز محشر انسانوں کا جسم کے ساتھ اٹھایا جاتا.بغیر مادہ کے دنیا کی تخلیق، کیا دنیا ابدی
ہے؟ نے فصل المقال میں انہی مسائل پر روشنی ڈالی ہے اور ایکوئے اس نے بھی اساتھیالیودیکا میں
انہی سب مسائل پر قلم اٹھایا ہے.کشف المناهج میں نے خدا کی ہستی ، خدا کی صفات تخلیق کا ئنات ،
مسئلہ قضا و قدر پر تفصیل سے لکھا ہے.دونوں مذہبی فلسفیوں نے ارسطو کے نظریات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی اپنی
مذہبی کتابوں بائبل اور قرآن کے عقائد کی فلسفہ سے تطبیق کی کوشش کی ہے.ایکوئے ناس اگر چہ کا مخالف تھا مگر در پر دو وہ بھی اس کے نظریات سے بڑی حد تک متاثر تھا اسی لئے
وہ کا نام بڑے احترام سے لیتا تھا.مثلاً نے کہا تھا کہ خدا کے علم سے موجودات جنم لیتی ہیں العلم
القديـم هـو عـلة وسبب للموجود (غير نفصل المقال).ایکوئے ناس نے بھی بالکل یہی کہا.سرناس
آرنلڈ نے لکھا ہے:
The Angelic doctor has made use of many of the arguments which the
Muslim doctor had previously employed.(44) کے سب سے مستند سوانح نگار رینان (1823ء 1892ء) کا کہنا ہے کہ "سینٹ نامس رشدی
تحریک کا سب سے بڑا مخالف ہے لیکن ہم متضاد بات کہے بغیر یہ کہنے کی بھی جرات کرتے ہیں کہ وہ شارح اعظم کا اول ترین شاگرد بھی ہے.البرٹ دی گریٹ نے تمام علم ابن سینا سے سیکھا جبکہ سینٹ ٹامس نے بطور فلسفی
سارا علم سے سیکھا" - ( 236 Averroes by E.Renan, 1852, page ).سینٹ ٹامس
ایکوئے ناس کی تصنیفات کے من دار مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ شروع میں ابن سینا سے متاثر تھا لیکن درجہ بدرجہ
اس کے خیالات سے ہم آہنگ ہونے لگے.لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ حیثیت ارسطو کے شارح کے دونوں ایک
دوسرے کے نظریات سے اتفاق نہیں کرتے تھے.مثلاً عقل کل ( Unity of Intellect) کو مانتا تھا
لیکن سینٹ ٹامس نے 1270ء میں ایک مقالہ لکھا جس میں اس نے کے نظریہ کی شدومد سے تردید کی.106
Page 125
مذہب اور فلسفہ
یہاں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی فلسفے پر طائرانہ نگاہ ڈالی جائے.فلسفہ اسلام جس کا دارو مدار قرآن
سنت اور علمائے اسلام کی مذہبی کتابوں پر بے یعنی ایسے مسائل جن کا تعلق شریعت سے ہے، ان میں سے چند بنیادی
مسائل درج ذیل ہیں: خدا کی ذات اور صفات کا مسئلہ تخلیق عالم کا مسئلہ.بغیر مادہ کے تخلیق عالم کا مسئلہ.کائنات
کے فانی یا غیر فانی ہونے کا مسئلہ قرآن کے تخلیق شدہ یا غیر تخلیق شدہ ہونے کا مسئلہ.روح کے فانی (مادی) یا
غیر فانی ہونے کا مسئلہ.انسانی زندگی کا مطمح نظر روز محشر جسموں کے اٹھائے جانے کا مسئلہ عقل اور الہام میں
فوقیت کا مسئلہ.قضا و قدر کا مسئلہ.خیر و شر کا مسئلہ.کائنات کے حادث یا غیر حادث ہونے کا مسئلہ، انسان کی آزادی
ارادہ کا مسئلہ.ان مسائل پر مذہب کیا کہتا ہے اور فلسفہ کا نقط نظر کیا ہے؟ یہ بہت وسیع مضمون ہے.اسلام ان مسائل
کے جو جوابات دیتا ہے اس کا نام اسلامی فلسفہ ہے.مثلاً مذہب اور فلسفہ میں ایک معرکۃ الآراء مسئلہ یہ رہا ہے کہ
کائنات حادث ہے یا قدیم؟ اسلام کا موقف یہ ہے کہ عالم تخلیق بالحق ہے لہذا وہ قدیم ہے حادث نہیں ، یعنی
کائنات مخلوق اور فانی ہے.اس کے برعکس ارسطو کا موقف یہ ہے کہ عالم مکان کے اعتبار سے حادث ہے لیکن باعتبار
زمانہ قدیم ہے.ابن سینا اور اس مسلک کے مرید تھے.نے فلسفے پر قلم اٹھاتے ہی ارسطو کو فلسفے میں اپنا پیشوا اور امام تسلیم کیا.اس نے اس کی تمام تصنیفات
ترتیب دیں، ان پر شر میں لکھیں اور بہت سے ان مسائل کی حمایت کی جو جمہور اسلام کے خلاف تھے.ان میں سے
ایک مسئلہ یہ تھا کہ افلاک ازلی ہیں.خدا نے ان کو پیدا نہیں کیا بلکہ خدا صرف ان کی حرکت کا خالق ہے.اس نے
دعوی کیا کہ اسلامی عقائد کی صحیح تشریح وہی ہے جو ارسطو کے نظریات کے موافق ہے.اس نے اشاعرہ کے خیالات کو
باطل ثابت کیا اور کہا کہ اشعری عقا کہ معقل اور نقل دونوں کے خلاف ہیں.بائبل کی تخلیق کی کہانی پر یقین نہیں رکھتا تھا اسے اس نے اسلامی تخلیق کائنات کا نیا نظریہ پیش کیا.اس کا یقین تھا کہ خدا ازل سے ہے، خدا ہی محرک اول (Prime Mover) ہے.قرآن مجید میں ہر قسم کی
صداقتیں موجود ہیں.اس کی آیات میں عام آدمی کے لئے ایک معنی اور فلاسفہ کے لئے اس کی آیات و الفاظ میں
دوسرے مطالب پوشیدہ ہیں.فلاسفہ کو چاہئے کہ وہ قرآنی آیات کی تفسیر اور معانی عام لوگوں کو نہ بتا ئیں.ابن سینا کی
طرح اس
کا یقین تھا کہ خدا ہر
شخص کی زندگی میں دلچسپی نہیں رکھتا ہے.اس کے اس طرح کے عقائد کی وجہ سے علما وفقہاء
کے اکسانے پر 1195ء میں اس پر شاہی عتاب نازل کیا گیا تھا.اس کے نظریات پر گہری نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے مذہب اسلام کے عقائد اور فلسفے کے
107
Page 126
اصولوں میں تطبیق کی پوری پوری کوشش کی.گویا اسلام اور عقلیت کے مابین مفاہمت اور مطابقت کا وہ سب سے
بر اعلمبردار تھا.در حقیقت بنیادی طور پر وہ نہایت مذہبی انسان تھا قرآن و حدیث پر مکمل عبور رکھتا تھا اسی لئے اس کی
تحریروں میں قرآن وحدیث کے حوالے جابجا ملتے ہیں.قرآن پاک کی وہ آیات جو متشابہات میں شمار ہوتی ہیں ان کی تاویل(interpretation) کے بارے میں
اس کا کہنا تھا کہ ان آیات کریمہ کی تاویل وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کا ذکر قرآن مجید (3:7 ) میں ہوا ہے و ما يعلم
تاويله الا الله والراسخون فی العلم ، اس کے نزدیک فلاسفہ ہی علم میں راسخ ہوتے ہیں اس لئے وہی ان کی
صحیح تاویل کرنے (ٹھیک مطلب بتانے ) کے حقدار ہیں.یا قرآن حکیم کی ایسی آیات مبارکہ جن میں خدا کے عرش
پر قائم ہونے کا ذکر ہوا ہے: ثم استوى الى السماء (2:29) - ثم استوى على العرش (7:54).معتزلہ نے ان آیات کی تاویل یہ کی کہ اس سے مراد خدا کا جاہ و جلال ہے جبکہ بعض لوگوں ( مراد ا شعری فرقہ ) کا کہنا
تھا کہ ان آیات کی حقیقت پر بلا کیف (بغیر سوال اٹھائے ) یقین کیا جائے.امام مالک بن انس (795 ء) کے
نزدیک آیات متشابہات کی تاویل کرنا بدعت اور خلاف شرع تھا.کہتا ہے کہ تاویل کرنے کے اصولوں سے
ہچکچاہٹ کی وجہ یہ ہے کہ اس کا تعلق قیاس (deduction, reasoning ) سے ہے جسے یونانیوں نے ایجاد کیا
تھا.(یادر ہے کہ اسلام میں تاویل کا سلسلہ سب سے پہلے الحق الکندی (873ء) نے شروع کیا تھا جیسے اس نے
آیت سخر الشمس والقمر کی تاویل یہ کی کہ اس سے مراد یہ ہے کہ سورج اور چاند قوانین فطرت کی پیروی
کرتے ہیں.( آج ہر کوئی اس تاویل سے اتفاق کرتا ہے.الکندی بہت بڑا فلسفی تھا، نہ کہ عالم دین ).اس قسم کے تعصب اور تنگ ذہنی کے خلاف کہتا ہے کہ فلسفہ در حقیقت کا ئنات کی اشیاء کی حقیقت و
ماہیت معلوم کرنے کا نام ہے.جہاں تک ان اشیاء کی ہستی کا تعلق ہے وہ اپنے بنانے والے کی طرف ہماری توجہ
مبذول کراتی ہیں.قرآن مجید ہمیں نہ صرف تفکر (reflection ) کی طرف توجہ دلاتا ہے بلکہ ترغیب دیتا ہے جیسے
اولم يننظروا في ملكوت السموات والارض و ما خلق الله من شیی ، (7:184 ) ( کیاده
آسمانوں اور زمین کی بادشاہت میں اور ہر چیز میں جو اللہ نے بنائی ہے ، تدبر نہیں کرتے.) فاعتبروا یا اولی
الابصار (59:2 ) ( پس اے صاحب بصیرت لوگو( دانش مندو) عبرت حاصل کرو.) پہلی آیت میں نظر سے مراد
critical evaluation ہے.امام الغزائی نے منطق کو آلات النظر کا نام دیا ہے یعنی ( Instrument of
Thought ).کا کہنا ہے کہ یہ ہمارا فرض ہے کہ قدماء (یونانی) کے بیان کردہ اصولوں اور قوانین پر غور
کریں، اگر وہ ہمارے عقائد کے مطابق ہیں تو ہمیں انہیں بخوشی قبول کر لینا چاہئے اور قد ما ء کا دل کھول کر شکر یہ ادا
کرنا چاہئے.اگر وہ غلط ڈگر پر ہیں تو ہمیں ان غلطیوں کی نشاندہی کرنی چاہئے.کیونکہ انہوں نے کوشش کی مگر نا کام
108
Page 127
ہوئے.(فصل المقال صفحه 6)-(45)
خدا تعالیٰ کے علم کے بارے میں اس کا کہنا تھا کہ قرآن مجید میں خداوند تعالیٰ نے اپنے وجود پر دو قسم کے بین
دلائل فراہم کئے ہیں: ایک کا نام دلیل عنالیہ اور دوسرے کا نام دلیل اختراع ہے.(1) دلیل عالیہ کی بنیاد دو اصولوں
پر ہے ایک یہ کہ دنیا کی تمام اشیاء انسانی ضروریات اور انسانی مصالح اور فوائد کے موافق ہیں دوسرے یہ موافقت
اتفاق نہیں بلکہ اس کو ایک ذی ارادہ ہستی نے پیدا کیا ہے.پہلے اصول کے مطابق دنیا کی اہم چیزوں مثلا دن،
رات، سورج، چاند، نباتات، جمادات پر غور و فکر سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ انسان کے لئے کس قدر مفید ہیں.اس
لئے جو خدا کے وجود کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے لئے موجودات کا مطالعہ اور تحقیق (ریسرچ ) ضروری ہے.(2) دلیل اختراع کی بنیاد بھی دو اصولوں پر ہے ایک یہ کہ تمام کائنات مخلوق ہے اور دوسرا یہ کہ جو چیز مخلوق ہے اس کا
ضرور کوئی خالق ہے.اس کے لئے جو اہر اشیاء کی حقیقت جاننا ضروری ہے.خدا تعالی کے علم کے بارے میں اس نے کہا کہ خدا کا علم انسانی علم جیسا نہیں ہے.یہ علم کی ایسی اعلیٰ وارفع قسم
ہے جس کے بارے میں انسان سوچ بھی نہیں سکتا.خدا کے علم میں اور کوئی ہرگز شریک نہیں.خدا کا علم اشیاء سے اخذ
نہیں ہوتا.جہاں تک روح کے غیر فانی ہونے کا تعلق ہے اس کا نظریہ تھا کہ روح اور عقل ( intellect ) میں فرق
کرنا چاہئے.عقل انسان میں دو چیز ہے جس کے ذریعہ انسان حواس خمسہ کے بغیر حقائق اور صداقتوں کا شعور حاصل
کرتا ہے.عقل فعال اور مادی عقل میں وہی فرق ہے جو صورت کا مادہ سے ہے.عقل فعال روح کے اندر قوت ہے
جو تمام انسانوں میں مشترک اور ازل سے ہے.اس کا کہنا تھا کہ ہر نبی فلسفی ہوتا ہے لیکن ضروری نہیں کہ ہر فلسفی نبی بھی ہو.نبوت اور فلسفہ میں ایک بنیادی
فرق یہ ہے کہ فلسفہ نام ہے حقیقت کی جستجو کا اور نبوت نام ہے کشف حقیقت کا فلسفی تو حصول علم میں لگارہتا ہے جبکہ
نبی حقیقت سے آشنا ہو کر دوسروں کو علم سکھاتا ہے، وہ حسن عمل کے حسین و سر در انگیز ثمرات کی خوشخبری دیتا ہے اور
برے اعمال کے حزن آفرین نتائج سے ڈراتا ہے.نبی کو غیر معمولی قلب سلیم ودیعت کیا جاتا ہے جس کے ذریعے وہ
بغیر خارجی تعلیم کے اشیاء کا علم از خود حاصل کر لیتا ہے.یعنی اس کے علم کا سر چشمہ اس کی عقل سلیم ہوتی ہے.لیکن
کشف والہام ہونے سے پہلے فلسفیانہ تفکر لازمی شرط ہے.اس شکل میں ہر نبی فلسفی ہوتا ہے.انبیاء کی ایک امتیازی
خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ ان کی عقل کا منبع قوت قدمی ہوتی ہے جس کے ادراک کا نام وحی ہے.یادر ہے کہ وحی ،
الہام اور رویائے صادقہ علم ایزدی کے اجزاء ہیں.انبیاء حقائق کا مشاہدہ اپنی قوت قدسی کے ذریعہ کرتے ہیں جن کا
اور اک عام لوگ نہیں کر سکتے.109.
Page 128
خدا پر ایمان خدا کا خالق و مالک ہونا ، خدا کا رب العالمین ہوتا، کائنات کی تخلیق ، نبوت کی حقانیت ، اور روز
محشر دوبارہ اٹھایا جاتا، یہ ایسے مسائل تھے جن کے بارے میں اس کا نظریہ تھا کہ ان کو ہر طور پر بلا حیل و حجت شرح
صدر سے تسلیم کرنا چاہئے.کہتا تھا کہ فلسفہ پیغمبروں میں ہمیشہ سے چلا آیا ہے، خدا کی رحمت ان لوگوں پر ہو:
i
Philosophy has always existed among the adepts of revelation i.e.prophets, peace be on them.فصل المقال میں اس نے فلسفہ کے مستحسن ہونے کے دلائل اسلامی شریعت سے اخذ کئے، اور کہا کہ قرآن
پاک میں مظاہر فطرت کے مطالعہ پر خاص تاکید کی گئی ہے (ان فی خلق السموت والارض واختلاف
الليل والنهار لايت لا ولی الالباب ) اور فطرت کے مطالعے کے لئے منطق اور دیگر سائنسی علوم کی تحصیل
ضروری ہے.خاص طور پر یونانی علوم کی.مگر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر سائنسی علوم کے مطالعہ سے حاصل شدہ نتائج
کتاب اللہ سے تناور کھتے ہوں تو پھر کیا کیا جائے؟ نے کہا کہ چونکہ دونوں صداقت کا ماخذ ہیں اس لئے
دونوں میں مطابقت تلاش کرنی چاہئے ، فرمایا:
Truth does not oppose truth, but accords with it and bears witness to it.اس حوالے سے مترشح ہوتا ہے کہ کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ وہ دوہری صداقت (Double
Truth) پر یقین رکھتا تھا ، وہ صریحاً غلط ہے.امر واقعہ یہ ہے کہ عمر بھر فلسفہ اور مذہب اسلام میں مطابقت
تلاش
کرتا رہا.وہ کہتا تھا کہ فلسفہ (سائنس) اور مذہب میں تضاد کی صورت میں انسان کو مذہب کے احکام پر عمل کرنا
چاہئے.فلسفہ کیا ہے؟ کائنات کی اشیاء کی حقیقت یا ماہیت کو معلوم کرنے کا نام فلسفہ ہے یا یوں کہا جا سکتا ہے کہ عالم
موجودات کے حقائق کے علم کا نام فلسفہ ہے.فلسفہ کی درج ذیل تعریف سے اس کے خدا کی ہستی پر مکمل یقین کا
اظہار ہوتا ہے:
"An inquiry into the meaning of existence and believe that God is the
order, force, and mind of the universe....."
یعنی فلسفہ ہمارے وجود کے معنی کے متعلق چھان بین اور اس بات پر یقین کا نام ہے کہ خدا اس کائنات کا کار
فرما، اس کی توانائی اور نفس ہے."
نکته برنج نکتہ شناس نے تلقین کی کہ ایسے فلسفیانہ خیالات صرف ان لوگوں کو بتلائے جائیں جو ایسے
110
Page 129
دقیق مسائل و امور میں مہارت رکھتے ہوں ، سادہ لوح عوام کو صرف سادہ خیالات جیسے کہانیاں، واقعات اور پرانے
( سبق آموز ) قصے سنا کر ان کے دل بہلائے جائیں.اس نے کہا کہ خدا نے انسان کو سوچنے کی صلاحیت ودیعت کی
ہے اور قرآن پاک میں خدا تعالیٰ نے انسان کو بار بار تاکید کی ہے کہ وہ اس سوچنے کی صلاحیت (لعلکم تعقلون ،
لعلكم تتفكرون ، لعلكم تنظرون ) کو بروئے کار لا کر اس کی آیات (یعنی مظاہر فطرت ) پر خوردند بر کرے
کیونکہ اس میں مفکروں اور دانش وروں کے لئے نشانات ہیں.مذہب اسلام کی فضیلت پر اس کا پختہ یقین تھا.اس نے کہا ہے کہ انسان کو اپنے زمانہ کی سب سے بہترین
مت کا انتخاب کرنا چاہئے اگر چہ اس کی نظر میں تمام متیں اچھی ہوں.جانا چاہئے کہ افضل شریعت کم تر شریعت پر
غالب آجاتی ہے یہی چیز اسکندریہ (مصر) میں ہوئی جب اسلام وہاں پہنچا تو وہاں کے علما اور دانشوروں نے اسلامی
شریعت کو اپنا لیا.یہی حالت روم کے علما کی ہوئی انہوں نے حضرت عیسی کی شریعت کو تسلیم کر لیا.بنی اسرائیل کی قوم
میں علما اور فقہا پیدا ہوتے آئے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہر نبی عالم فلسفی ہوتا ہے لیکن ضروری نہیں کہ ہر عالم ( فلسفی ) نبی
ہو.علم بلا شبہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں ( علما ورثۃ الانبیاء ( الفارابی (950ء) کے نزدیک فقط فلسفی ہیں
انسان کامل ہوتا ہے.(46)
كتاب تهافت التهافة اور پر یہ الزام عائد کیا جاتا ہے کہ وہ انسانی روح کی بقائے دوامی کا انکار
کرتا تھا کیونکہ بقول اس کے انفرادی روح موت کے بعد آفاقی روح Universal Soul) میں ضم ہو جاتی
ہے.امر واقعہ یہ ہے کہ جو کچھ نے کہا اس کا اطلاق صرف عقل ( intellect) پر ہوتا ہے.کے
نظام فکر میں روح کا عقل سے امتیاز ضروری ہے اور نہ صرف بلکہ دوسرے مسلمان فلاسفہ کے مطالعے میں بھی
یہ امتیاز ضروری ہے.عقل انسان کی وہ ذہنی صلاحیت ہے جس کے ذریعہ وہ بغیر حواس خمسہ کے آفاقی صداقتوں سے
آگاہ ہوتا ہے جیسے ریاضی کے اصول، سوچنے کے اساسی قوانین وغیرہ (47) اور افلاطون کی جس کتاب نے یورپ پر سب سے زیادہ اثر چھوڑ او د افلاطون کی کتاب ری پبلک کی جوامع یا
شرح متوسط (1177ء) ہے.یہ کتاب اصل عربی میں تو مفقود ہے البتہ اس کے عبرانی ترجمے سے انگریزی میں اس
کا ترجمہ روزن تھال (E.J.Rosenthal) نے کیا ہے جو کیمبرج یونیورسٹی سے 1956 ء میں شائع ہوا ہے.روزن تھال نے اپنا انگریزی ترجمہ آنھے عبرانی مخطوطات کے مطالعہ سے تیار کیا جو یورپ کی مشہور جامعات ( میونخ
فلورنس ، وی آنا ، آکسفورڈ ، ملان، کیمبرج) میں موجود ہیں.نے شرح متوسط حسین ابن الحق کے عربی ترجمہ
111
Page 130
سے تیار کی تھی.ری پبلک کا انتخاب اس نے اس لئے کیا کیونکہ ارسطو کی کتاب سیاسیۃ (Politics) اس کے ہاتھ
نہ لگ سکی (افلاطون کی جمہوریہ صفحہ 4)
کتاب کے بنظر غائر مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے یونانی فلسفہ اور مذہبی قوانین میں تطبیق
(synthesis) کی کامیاب کوشش کی اور یہی چیز اس کی فلسفیانہ زندگی کا طرہ امتیاز ہے.اس نے افلاطون کے سیاسی
فلسفہ کو اپنے فلسفہ کے طور پر اسلامی ریاست پر منطبق کیا.اس کے نزدیک اسلامی شریعت کے قوانین افلاطون کے
آئیڈیل، فلسفی بادشاہ کے قوانین (Nomos) سے افضل ہیں.اسلامی شریعت کی تعلیمات اتنی اعلیٰ اور پیچیدہ ہیں
کہ انسانی فہم سے باہر ہیں.ان پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے کیونکہ اس میں الہامی صداقتیں موجود
ہیں.اس کے نزدیک اسلامی طرز حکومت جس کا آئیڈیل دستور اسلامی شریعت ہے افلاطون کی جمہوریت سے
ہزار درجہ بہتر ہے.اس نے افلاطون کے نظریہ سے اتفاق کیا کہ آئیڈیل اسٹیٹ ٹرانسفارم ہو کر چار ریاستوں میں بدل
جاتی ہے (ٹیموکریسی، آلی گار کی ، ڈیموکریسی ، ٹیرانی).یہی چیز حضرت معاویہ کے دور میں ہوئی جب خلافت راشدہ
آئیڈیل اسٹیٹ سے تبدیل ہو کر شخصی حکومت ( ٹیمو کریسی) بن گئی.اس کی زندگی میں یہی چیز مرابطون اور موحدون
کے دور حکومت میں ہوئی جو شرعی حکومتیں تھیں مگر بعد میں بدل گئیں.ایک مخلص زاہد مسلمان کی حیثیت سے اس نے کہا
کہ سید الانبیا ع خاتم النبین تھے جنہوں نے اسلامی شریعت کو ہر زمانے اور دور کے لئے نافذ کیا.(48) اور امام غزالی
حجتہ الاسلام امام غزالی (1111-1058ء) عظیم المرتبت مفکر ، صوفی حکیم اور معلم اخلاقیات تھے.شہرہ آفاق
کتاب تهافة الفلاسفة لکھنے کے بعد وہ شہرت کے پروں پر از نے لگے.نے اس کے جواب میں
تهافة التهافة لکھ کر علمی حلقوں میں تہلکہ مچایا.کے نزدیک الغزائی معقلیت پسند فلسفی تھے مگر انہوں نے
شہرت حاصل کرنے کے لئے تصوف کا لبادہ زیب تن کیا اور رہبانیت اختیار کی.ان کا دماغ فلسفی کا اور دل صوفی کا
تھا اور دل ودماغ میں یہ کھینچا تانی عمر بھر جاری رہی.ان کی فکری زندگی میں سب سے
نمایاں چیز جو نظر آتی ہے وہ ان
کی تشکیک پسندی (scepticism) ہے.یہ کوئی بری چیز نہیں بلکہ ہر عبقری محقق کی پہچان ہوتی ہے کہ اس میں بیک
وقت دور، محانات پائے جاتے ہیں یعنی سلبی اور ایجابی سلبی رجحان تشکیک پر آمادہ کرتا ہے اور ایجابی ایمان کا مظہر
ہوتا ہے.امام غزالی بظاہر فلسفے کے مخالف تھے لیکن ان کے نظام فکر میں جو مسئلہ بنیادی حیثیت رکھتا ہے وہ عقلیت ہے.انہیں عقل پر سب سے بڑا اعتراض یہ تھا کہ عقل تنہا حقیقت کا ادراک نہیں کر سکتی اس لئے معرفت کے معاملات میں
112
Page 131
اس کی تصدیقات یقینی نہیں ہو سکتیں.وہ چونکہ معقولات ( علوم حکمت ، فلسفہ، منطق ) کو غیر معتبر سمجھتے تھے اس لئے
اسے فلسفیوں کی انہوں نے مخالفت کی جو علم و معرفت کو محض عقل کا مرہون منت خیال کرتے تھے.ان کے نزدیک
حقیقت کے عرفان کے لئے عقل کے بجائے صوفیانہ مجاہدے ( religious experience) سے کام لینا چاہئے
جسے دور جدید میں فلاسفہ وجدان ( intuition) کہتے ہیں.امام غزالی اگر چہ عقل کی قطعیت کے قائل نہیں تھے لیکن وہ عقل کو برا بھی نہیں سمجھتے تھے اور نہ اس کی افادیت
سے انکار کرتے تھے.امام غزالی نے فلسفیانہ اصطلاحات کثرت کے ساتھ مذہبی ذخیرہ میں داخل کیں.انہوں نے
دین کی حمایت میں فلسفے کے طلسم کو توڑنے کے لئے اسے عام فہم بنایا.انہوں نے ثابت کیا کہ فلسفہ محض غور وفکر کا نام
ہے اور فلسفیانہ افکار ہر کسی کی سمجھ میں نہیں آسکتے.نیز صرف فلسفہ ہی حقیقت مطلقہ تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا.انہوں نے فرمایا کہ اگر چہ یہ درست ہے کہ حقیقت کا عرفان صرف عقل ہی کے ذریعہ ہوتا ہے لیکن عام عقل سے نہیں،
بلکہ اس کے لئے عقل سلیم کی ضرورت ہوتی ہے.عقل میں حسن ونور پیدا کرنے کے لئے تزکیہ نفس کی ضرورت ہوتی
ہے جس کا صوفیا نہ نام مجاہدہ نفس ہے.(19)
تصافة الفلاسفة میں انہوں نے یونانی فلاسفہ اور ان کے مسلمان شارحین ( الفارابی ، ابن سینا) کے نظریات
کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کی ہے.اس کے برعکس نے اپنی کتاب میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ
غزالی نے جن فلسفیانہ خیالات کی تردید کی ہے وہ یونانی نہیں تھے.بلکہ ان میں بعد کے فلسفہ کے نظریات کا امتزاج
ہے.نے کہا کہ غزالی کا طریقہ غیر منطقی ہے اور وہ ایک خاص مذہبی مسلک کے نقطہ نظر سے بحث کرتے ہیں
اس لئے ان کا محاکمہ غیر معتبر اور غلط ہے.انہوں نے اپنے زمانے کے سلاطین، علما اور رعایا کی خوشنودی کے لئے
ایسا کیا.بقول غزالی بظاہر فلسفے کے مخالف تھے لیکن در حقیقت وہ فلسفے کے حامی تھے.انہوں نے فلسفے کی
بہت خدمت کی ، ایجابی اور سلبی ہر لحاظ سے.ایجابی لحاظ سے یوں کہ انہوں نے فلسفیانہ فکر کو گراں سے بچانے اور صحیح
خطوط پر چلانے کی کوشش کی پہلی اس لحاظ سے کہ انہوں نے فلسفہ کے باطل نظریات کی تردید کی.تهافت الفلاسفة
فلاسفہ کے جن 20 دعووں کی امام غزالی نے تهافت الفلاسفة میں تردید کی ہے وہ درج ذیل ہیں:
1.اس دعوی کا ابطال کہ عالم ازلی ہے: غزالی نے فلاسفہ کے اس نظریے کی تردید کی ہے کہ عالم یا کائنات قدیم
سے ہے.کا کہتا ہے کہ غزالی نے اس نظریہ کو سمجھا نہیں، اگر سمجھا تو اسے غلط طور پر پیش کیا اور غلط
113
Page 132
مفروضات قائم کر کے اسے جھٹلایا.-2 ابدیت عالم کا ابطال: دنیا ہمیشہ سے چلی آرہی ہے اور ہمیشہ چلتی رہے گی ؟
-3 خدا اس عالم کا صانع نہیں ہو سکتا اس سلسلے میں حکما کی دھوکہ دہی : فاعل وصانع میں ارادہ و اختیار کی صفات کا ہونا
ناگزیر ہے.خدا واحد ہے اور واحد سے کثرت کا صدور ناممکن ہے، اس لئے اس دنیا کی بوقلمونی کی کوئی توجیہ
نہیں ہو سکتی.-4 خدا کا وجود ثابت کرنے میں حکما عاجز ہیں: فلاسفہ اللہ تعالیٰ کا وجود ثابت نہیں کر سکتے.فلاسفہ عالم کو قدیم وازلی
بھی مانتے ہیں اور اس کے ساتھ اس بات کے قائل ہیں کہ عالم کے قدیم ہونے کے باوجود اس کی علت ہونی
چاہئے.5- فلاسفہ خدا کی توحید ثابت نہیں کر سکتے : فلاسفہ یہ ثابت کرنے سے عاجز ہیں کہ ایک سے زائد واجب الوجود فرض
نہیں کئے جاسکتے.-6.کیا ذات وصفات کی روئی کا مسئلہ کثرت کا سبب ہے؟ یعنی فلاسفہ کے اس دعوے کا ابطال کہ خدا میں صفات
نہیں پائی جاتیں ہمثلاً خدا تعالی قدرت علم اور ارادہ کی صفات سے معرا ہے.7 تعدد و کثرت کا دوسرا سبب: فلاسفہ کا یہ دعوئی غلط ہے کہ خدا کے یہاں جنس و فصل نہیں.بالفاظ دیگر مبدء اول
( First Cause ) کو جنس و فصل کے ذریعے بیان نہیں کیا جاسکتا.8 - فلاسفہ کا یہ دعوئی ثابت نہیں ہو سکتا کہ خدا کی ذات بسیط محض بلا ماہیت ہے.9.فلاسفہ خدا کی جسمیت کا انکار نہیں کر سکتے ؟ جسم قدیم اور جسم حادث میں فرق؟ فلاسفہ یہ ثابت کرنے سے معذور
ہیں کہ خدا کا جسم نہیں.10 - فلاسفہ اثبات صانع سے قاصر ہیں.علت العلل کے اثبات سے صانع کا وجود ثابت نہیں ہوتا.11- فلاسفہ یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ خدا تمام کائنات کے بارے میں کلی اور اک رکھتا ہے ، خدا اپنے سوا کسی اور کو
جانتا ہے ؟
12 - فلاسفہ مبدء اول سے متعلق اس حقیقت کا اثبات نہیں کر سکتے کہ اسے اور اک ذات حاصل ہے، فلاسفہ یہ
ثابت نہیں کر سکتے کہ خدا اپنی ذات کا علم رکھتا ہے.13.فلاسفہ کے اس دعوی کی تردید کہ خدا کیات کا علم تو رکھتا ہے گر جزئیات کا نہیں.114
Page 133
14.فلاسفہ کا یہ دعوئی غلط ہے کہ آسمان حیوان متحرک بالا رادہ ہے: فلاسفہ اپنے اس دعوے کو ثابت نہیں کر سکتے کہ
آسمان ایک حیوان ہے جو اپنی حرکت دور یہ سے خدا کے حکم کی اطاعت میں مصروف ہے.15 - فلاسفہ نے حرکت افلاک کی جو غرض بیان کی ہے، وہ باطل ہے : فلاسفہ کا دعویٰ ہے کہ افلاک صرف زندہ ہی
نہیں بلکہ اطاعت خداوندی کا فریضہ بھی ادا کر رہے ہیں اور ان کا مقصد تقرب خداوندی ہے.16.یہ بات غلط ہے کہ نفوس سماوی تمام جزئیات کو جانتے ہیں، نیز یہ بھی غلط ہے کہ لوح محفوظ سے مراد نفوس کا دیہ
ہیں.17.فرق عادات کا انکار باطل ہے.ضروری نہیں کہ دو چیزوں کا عادةً مل کر کوئی نتیجہ پیدا کر نا علیت و معلولیت کی
بناء کچہ ہو.18 - فلاسفہ یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ روح ایک جو ہر ہے جو نہ جسم ہے نہ عرض.19.فلاسفہ کے اس دعوے کے ابطال میں کہ نفوس انسانی سرمدیت کے حامل ہیں.فلاسفہ یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ
روح ابدی ہے.20 - فلاسفہ جو قیامت اور حشر اجساد کے منکر ہیں، یہ ان کی فروگذاشت ہے.مذکورہ بالا مسائل میں سے سولہ مابعد الطبعیاتی اور چار طبعیاتی ہیں.امام موصوف نے صرف آخری تین مسائل
میں فلاسفہ کی تکفیر کی اور باقی کے متعلق کہا کہ ان کا مذہب سے
کوئی تعلق نہیں ہے.نیز اکثر جگہ انہوں نے محض فلاسفہ
کی دلیلیں رد کی ہیں ورنہ فلاسفہ خودان مسائل کے خلاف نہ تھے.مثلاً متکلمین کی طرح فلاسفہ بھی خدا کی وحدانیت کو
مانتے ہیں اور اس کے حق میں عقلی دلائل دیتے ہیں مگر حجۃ الاسلام امام غزالی نے فلاسفہ کے اس خیال کو بھی رد کیا
حالانکہ اس کا رد کرنا ضروری نہ تھا.علم ریاضی، جیومیٹری ، منطق اور علم اخلاق کے مسائل پر امام کے خیالات غیر جانبدارانہ تھے.کیونکہ ان علوم کا
اثر مذہب پر کم ہے.منطق بقول ان کے سوچنے کا آلہ (آلات النظر) ہے اور اس کا استعمال انہوں نے فلاسفہ کے
خلاف خوب کیا.تیسرے اور چوتھے سوال میں فلاسفہ منافقت اور ریا کاری کے مرتکب ہوئے.سوال نمبر چھ سے تو
تک کا تعلق فلاسفہ کے خدا کی صفات پر نظریہ سے ہے.سوال
نمبر سترہ کا تعلق علت اور معلول کے باہمی تعلق سے
ہے.آخری دو سوالوں
کا تعلق روح کی ابدیت اور حشر و نشر سے ہے.فلاسفہ نے روح کی ابدیت کے بارے میں جو
ثبوت دئے امام غزالی نے ان کا تجزیہ کیا اور کہا کہ یہ غیر فیصلہ کن ہیں.فرمایا کہ روح جسم کی موت کے بعد زندہ رہتی
ہے، جیسا کہ فلاسفہ مانتے ہیں.لیکن یہ روز محشر دوبارہ اس جسم میں واپس آجائے گی یا اس جسم سے ملتے جلتے جسم
115
Page 134
میں، اس بات کا فلا سفہ انکار کرتے ہیں.روز محشر دوبارہ زندہ ہونے والے جسم میں روح شعوری اور روحانی راحتوں
سے محفوظ ہو سکے گی، بلکہ بعض جسمانی لذتوں سے بھی جس کا فلاسفہ انکار کرتے ہیں.قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے:
فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانو يعملون (32:17) کسی شخص کو خبر نہیں جو
آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ایسے لوگوں کے لئے خزانہ غیب میں موجود ہے، یہ ان کے اعمال کا صلہ ہے.(تهافت
الفلاسفة صفحه 355 انگریزی ترجمہ )
امام غزالی کی شہرہ آفاق تصنیف تهافت الفلاسفة کے بارے میں کا کہنا تھا کہ : " غزالی نے
تهافت الفلاسفہ میں تین مسائل میں فلاسفہ کی تکفیر اس بناء پر کی کہ انہوں نے خرق اجتماع کیا.یہ کتاب
مجموعه اباطیل و شبھات ہے.(کشف الادلہ صفحہ 72 ).کے نزدیک اس کتاب کی کوئی
وقعت نہ تھی کیونکہ وہ اس کے دلائل کو برہان سے کم درجہ کے سمجھتے تھے.یعنی ان کے دلائل محض لغو اور مہمل تھے.ان
کے نزدیک امام صاحب فلسفہ میں کچے تھے کیونکہ الفارابی اور ابن سینا کے فلسفہ کے علاوہ وہ کچھ نہیں جانتے
تھے.دراصل غزالی قارئین کو حیرت میں ڈال کر اپنا نفوذ قائم کرنا چاہتے تھے.عجیب بات یہ ہے کہ امام غزالی نے فلاسفہ کے نظریات کو غلط ثابت کیا لیکن یہ بتانے سے اعراض کیا کہ ان کی
اپنی رائے ان مسائل کے بارے میں کیا تھی؟.کے نزدیک انہوں نے ایسا ذاتی مصلحت کی بناء پر کیا، ورنہ
دل سے وہ فلاسفہ کے ہم نوا اور ہم خیال تھے.بہر حال غزالی نے تسلیم کیا کہ ان کا مقصد صرف ان فلسفیانہ نظریات کی
تردید تھا نہ کہ تحقیق.مزید فرماتے ہیں کہ امام غزالی اپنے قول میں مخلص نہ تھے.ان میں اور فلاسفہ میں
اختلاف محدود تھا.انہوں نے فلاسفہ کے نظریات کی تردید اس لئے کی تا کہ اہل سنت میں اپنا اثر و رسوخ قائم کر
سکیں.ابن طفیل بھی کے اس خیال کی تائید کرتا تھا کہ غزالی نے جو کچھ فلسفے کے خلاف لکھا اس کی علت غائی
عوام اور خواص کی خوشنودی حاصل کرنا تھا، جو عقلیت کے دشمن اور تقلید کے دلدادہ تھے.یہ بھی یادر ہے کہ مذکورہ
نظریات ارسطو کے تھے اور امام غزالی نے یونان کے فلاسفہ خاص طور پر ارسطو کی فضیلت کا اعتراف داشگاف الفاظ
میں کیا ہے.اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ امام صاحب ارسطو کے نظریات کے معترف تھے.نے امام غزالی کی کتاب کا رولکھا تو علمائے اسلام نے اس پر شدید تنقید کی اور عالم اسلام میں اس کا
منفی رد عمل ہوا.چنانچہ اس کی کتاب کے رد میں ترکی کے عالم مصطفیٰ ابن یوسف البر صادی (خواجہ زادے 1487ء)
نے تهافت التهافت التهافی لکھی.عالم اسلام میں امام غزالی کی کتاب کا اثر یہ ہوا کہ لوگوں نے فلسفہ اور سائنس
116
Page 135
کی تعلیم سے تعلق ختم کر لیا اور وہ اجتہاد کا دروازہ بند کر کے تقلید کرنے لگے.اس کا نتیجہ سب کے سامنے ہے عالم
اسلام میں ترقی رک گئی اور لوگوں نے اپنی سوچ پر پہرے بٹھا لئے.مسلمانوں کی حالت نا گفتہ بہ ہوگئی.آج عالم
اسلام کی حالت دگرگوں ہے.اور سات سو سال بعد بھی مادی، سماجی، سائنسی، روحانی اور علمی ترقی نام کو نہیں ہے.تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ مسلمانوں کے عروج کی تاریخ کا آغاز ٹھیک اس وقت ہوا جب ان میں علم و حکمت کی
طلب و جستجو پیدا ہوئی اور وہ ان علوم کے قدر شناس ہوئے.اسی طرح ان کے انحطاط کے آغاز کا زمانہ بھی وہ ہے
جب ان میں علم و حکمت کی طلب سلب ہو گئی.اس کے برعکس یورپ میں وہاں کے فضلا نے کو اپنا امام اور
علمی پیشوا تسلیم کیا اس کے نتائج بھی سب کے سامنے ہیں.بارہویں صدی میں کی وفات کے بعد یورپ
ترقی کے راستہ پر گامزن ہونا شروع ہوا، آج یورپ اور امریکہ ہر قسم کی ترقی کے میدان میں عالم اسلام سے ایک ہزار
سال آگے ہیں.یورپ نے کو اپنابنا کر عالمی تاریخ کا رخ موڑ دیا.کاش ہم اس بات کو سمجھ سکیں اور کو اپنا ئیں، ہماری ترقی اسی میں مضمر ہے.اور غزالی کے مابین علمی اختلاف آج سے آٹھ سو سال قبل مفکرین اسلام کے مابین تنازع کی عمدہ
مثال ہے.جہاں تک علت اور معلول (cause and effect) کے مسئلہ کا تعلق ہے غزالی کے نقطہ نظر کے
مطابق تمام اعمال، حادثات طبعی واقعات یا جو کچھ بھی ہو، یہ خدا کی مداخلت کی وجہ سے وقوع پذیر ہوتے ہیں.ان
کی منطق کے مطابق آگ کپڑے کو شعلہ زن کرتی ہے اس لئے نہیں کہ آگ کی یہ فطرت ہے کہ دو جلائے ، بلکہ مافوق
الفطرت ہستیوں جیسے فرشتوں کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے.کے نزدیک یہ حماقت کی انتہا ہے کہ جب بھی آگ
لگتی ہے ان گنت فرشتے آسمان سے نازل ہو کر ایسا کرتے ہیں.علل طبعی سے عمل طبعی جنم لیتی ہے.ہر کوئی آئے روز
کے تجربہ سے جانتا ہے کہ جب کپاس کو آگ کے قریب لے جایا جائے گا تو یہ شعلہ زن ہو جائے گی، کیونکہ کسی نے
آج تک اس کے برعکس ہوتے نہیں دیکھا.تھافة التهافة میں اس نے کہا کہ عمل سے انکار علم سے انکار ہے اور علم
سے انکار کا مطلب ہے کہ کسی بھی چیز کا علم اس دنیا میں حاصل نہیں کیا جا سکتا.(51)
نہ چھوڑا.بقول جارج سارٹن تھافة التهافة نے مسلمانوں میں بہت مقبولیت حاصل کی لیکن اس نے ان پر کوئی اثر
عقل ایسی شے ہے کہ کوئی اور شے حقیقت میں اس کے مثل نہیں.اس لئے عقل کو آفتاب کی مثال کہا جا سکتا
ہے کیونکہ عقل اور سورج میں ایک مناسبت ہے.نور آفتاب سے محسوسات کا انکشاف ہوتا ہے اور نور عقل سے
معقولات کیا.117
Page 136
اور ابن سینا
شیخ الرئیس (بادشاہ علم و حکمت) ابوعلی ابن سینانہ صرف بین الاقوامی طبیب بلکہ عظیم فلسفی بھی تھا.دانش نامہ علائی
میں اس نے منطق ، حکمت خداوندی علم فلکیات، موسیقی اور ریاضی جیسے دقیق موضوعات پر خامہ فرسائی کی.فلسفہ میں
اس کی دوسری معرکۃ الاراء تصنیف کتاب الشفاء ہے.ابن سینا کو طب، فلسفہ اور دوسرے علوم کی تدوین و ترتیب
میں بہت شہرت حاصل ہوئی.منطق میں اس نے نئی چیزیں ایجاد کیں لیکن فلسفہ میں وہ ارسطو کا مقلد تھا.جس چیز
نے اس کو ان علوم میں افضل مقام عطا کیا وہ یہ تھا کہ اس نے فلسفہ و منطق کو منظم و مرتب کیا اور مبتدی منتہی اور متوسط
ہر طبقہ کے لئے کتا میں لکھیں.اس لئے اس
کی کتا ہیں یو نیورسٹیوں کے نصاب تعلیم کا حصہ بن گئیں.اس کی ایک اور
امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ اس نے فلسفہ اور اسلامی عقائد میں تطبیق پیدا کی.ہاں الہیات میں اس نے ارسطو کے
فلسفہ کا ڈھانچہ بالکل بدل دیا، اور متکلمین کے ایسے اقوال شامل کئے جن کا ارسطو یا حکماے یونان سے کوئی تعلق نہ
تھا.بقول اس نے اپنے کئی نظریات ارسطو کے نام سے منسوب کر دئے.الہیات (تھیالوجی) کا ایک مسئلہ یہ ہے: الواحد لا يصد رعنه الواحد یعنی ایک چیز سے صرف ایک
چیز ہی پیدا ہو سکتی ہے.تاہم یہ مسئلہ ابن سینا کی ایجاد ہے.لکھتا ہے: " یہ غلط ہے کہ تم اس قول کو قدماء کی
کتابوں میں دیکھو، ابن سینا وغیرہ کی کتابوں میں نہ دیکھو، جنہوں نے علم انہی میں (یونانیوں) کے مذہب کو بالکل
بدل کے رکھ دیا.(تهافته النهافة صلح 49) مسئله اثبات فاعل کے متعلق کہتا ہے.اگر چہ ابو نصر فارابی اور ابن سینا کے متعلق خیال کیا جاتا ہے کہ
انہوں نے اس مسئلہ میں کہ ہر فعل کے لئے ایک فائل کا ہونا ضروری ہے، یہی مسلک اختیار کیا ہے لیکن یہ قدماء کا
مسلک نہیں بلکہ ان دونوں نے اس میں ہمارے ہم مذہب متکلمین کی تقلید کی ہے.( تهافته النهافة صفحہ 17 ) نے کتنی مسائل کے متعلق انکشاف کیا کہ وہ ابن سینا کی ایجاد ہیں.ایک مسئلہ کے متعلق لکھتا ہے:
سخت تعجب ہے کہ ابونصر اور ابن سینا سے یہ بات کیونکر پوشیدہ رہی.کیونکہ سب سے پہلے ان دونوں نے یہ بات کہی
اور دوسرے لوگوں نے ان کی تقلید کی.اور اس قول کو فلاسفہ (یونان) کی جانب منسوب کر دیا" (صفحہ 65) پھر ایک
اور جگہ لکھتا ہے : " یہ تمام اقوال ابن سینا کے ہیں، اور جس نے اس جیسی بات کہی تو وہ اقوال غلط ہیں اور فلسفہ کے
اصول کے مطابق نہیں ہیں." (صفحہ 66) ایک اور انکشاف یہ کیا کہ " یہ بات کہ ہر جسم ہیوٹی اور صورت سے مرکب
ہے، تو اجرام کاریہ میں یہ فلاسفہ کا مذ ہب نہیں ، یہ بات صرف ابن سینا نے کہی ہے." ( نیافته التهافت صفحہ 71)
118
Page 137
الہیات کے مذہبی مسائل یونانیوں کی الہیات میں موجود نہیں تھے.ابن سینا نے پہلی مرتبہ ان مسائل کو الہیات
میں شامل کیا.مثلاً حشر اجساد کے انکار کے متعلق پرانے فلاسفہ کا کوئی قول نہیں ملتا ہے.اسی طرح پرانے فلاسفہ نے
معجزات پر کوئی بحث نہیں کی.کہتا ہے : " ان کے مبادی امور طبیہ میں ہیں جو عقل انسانی سے بالا تر ہیں.اس لئے باوجود ان کے اسباب کے نہ معلوم ہونے کے ان کا اعتراف کرنا چاہئے ، کیونکہ قدماء ( یونانی فلاسفہ ) میں
سے کسی نے معجزات پر کلام نہیں کیا " ( تهافته التهافة صفحہ 124)
علم الہیات میں ابن سینا نے اس قدر اضافے اور تبدیلیاں کیں کہ اس کی شکل ہی بدل گئی.اس کی وجہ یہ تھی کہ
یونانیوں
کا علم الہیات بہت ناقص تھا اس لئے جب تک اس میں متکلمین اسلام کی آراء شامل نہ کی جاتیں، یہ علم نامکمل
رہتا.اس کے علاوہ ابن سینا نے حکماے قدیم سے بہت سے مسائل میں اختلاف کیا.اس اضافے اور اختلاف کا
مقصد حکمت اور شریعت میں تطبیق پیدا کرنا تھا.ابن سینا نے ایک اور بڑا علمی کام یہ کیا کہ اس نے تصوف کو علمی
اصولوں پر مرتب کیا، اور اس کے مسائل کو عقلی دلائل سے ثابت کیا.(52)
جارج سارٹن کی رائے
اس باب کو ہم جارج سارین کی رائے پر ختم کرتے ہیں."Ibn Rushd's originality appeared chiefly in his way of interpreting anew
the teachings of the wise men who had come before him.He was
primarily a realist, a rationalist.His superiority over Ibn Sena and other
Muslim philosophers lay partly in his better knowledge of Aristotle.Ibn
Rushd's philosophy was essentially a return to scientific philosophy
opposite tendencies of
the
largely stimulated by
which was
Al-Ghazali.Ibn Rushd was at once the greatest and the last of their
philosophers." (53)
119
Page 138
باب ششم کے نظریات یورپ میں
یورپ کی نشاۃ ثانیہ اور حیات ثانیہ کے ذکر سے لبریز ہے.وہ عقلیت کا زبردست نقیب تھا.سات سو
سال تک عالم اسلام میں گمنام رہا.اس کی تصنیفات اصل عربی زبان میں اس وقت یورپ سے شائع ہونا شروع
ہوئیں جب 1859 ء میں ایم جے میولر ( MJ.Muller) نے میونخ سے فصل المقال اور کشف الادلہ کو ایک
مجموعے کی صورت میں طبع کرایا.اس کے بعد 1875ء میں بورین اکیڈیمی (Bavarian Academy) نے
یہی دو کتابیں میولر کے جرمن ترجمے کے ساتھ شائع کیں.پھر عربی میں یہ قاہرہ سے 95-1894 ء میں شائع
ہوئیں.اس کا فرانسیسی ترجمہ و تعییر (Gauthier) نے 1905ء میں کیا جبکہ انگریزی ترجمہ جمیل الرحمن نے کیا جو
بزودہ (ہندوستان ) سے 1921ء میں شائع ہوا.حیدرآباد سے ایک شاندار کتاب رسائل 1947ء
میں منظر عام پر آئی جس میں چھ کتابوں کی تلا حیص شامل ہیں.جیسا کہ ذکر کیا گیا کی تصانیف کی تعداد 87 سے زیادہ ہے.ان کتابوں کی اکثریت اسکور یال
(اسپین) کے کتب خانے میں موجود ہے.تاہم اس کے علاوہ اس کی کتابیں امپیریل لائبریری پیرس، بوڈلین
لائبریری ( آکسفورڈ) ، لانش این لائبریری ( فلارنس، اٹلی) دی آنالائبریری ( آسٹریا)، ساربون (فرانس) اور
لائیڈن (ہالینڈ) میں موجود ہیں.پیرس اور ( بوڈلین ) آکسفورڈ میں بعض ہاتھ سے لکھے عربی نسخے عبرانی رسم الخط
میں لکھے ہوئے ہیں جن سے یہودی عالم استفادہ کیا کرتے تھے.کی اصل عربی کتابوں کے مخطوطات
یورپ میں کم ہیں لیکن ان کے لاطینی اور عبرانی تراجم یورپ کے تمام قابل ذکر کتب خانوں میں موجود ہیں.تھافتہ
النصاف کا لاطینی ترجمہ 13238ء میں کیا گیا کہتے ہیں کہ عبرانی زبان میں توریت کے بعد کی تصنیفات
سے زیادہ کسی اور مصنف کی کتابوں کی اشاعت نہیں ہوئی.کی کتابوں کے لاطینی تراجم جو 1480 ء سے لے کر 1580ء تک سو سال کے عرصہ میں منظر عام پر
120
Page 139
آئے ان کی تعداد ایک سو سے متجاوز تھی.صرف دینیس (اٹلی) کے مطبع خانے سے اس کی کتابوں کی جو مختلف اشاعتیں
نکلیں وہ پچاس سے زیادہ تھیں.1482ء میں کتاب الکلیات اور رسالہ جواهر الکون شائع ہوئیں،
پھر 1483ء میں ارسطو کی مکمل تصنیفات کی شروح اور تلخیصات کے ساتھ شائع ہوئیں.پیڈ وا یو نیورسٹی
(اٹلی) کے مطبع خانے نے پندرہویں صدی میں اس کی تصنیفات کا حق طباعت اپنے لئے محفوظ کر رکھا تھا، کیونکہ اب
کتابیں پرنٹنگ پریس پر چھپنا شروع ہو گئی تھیں.یہ چیز قابل غور ہے کہ 1500 ء سے لے کر 1550 ء تک کی وہ کتابیں جن کا تعلق ارسطو سے تھا ان
کے تراجم عبرانی سے لاطینی میں کئے گئے.تراجم کا یہ کام زیادہ تر اٹلی میں ہوا.چنانچہ سولہویں صدی کے نصف
میں گیارہ جلدوں میں ارسطو ایڈیشن شائع ہوا.پھر و فیس سے تین مزید تختیم ایڈیشن شائع ہوئے.لیو آن
(Lyon) فرانس سے کی شرحوں پر یور چین شرمیں اسی عرصے میں شائع ہوئیں.(54)
سب سے پہلے جس شخص نے عبرانی میں اس کی کتب کے ترجمے کئے وہ جیکب اناطولی نیپلس
(Jacob Anatoli Naples ) تھا اس کے بعد جوزا کو ہن (Judah Cohen نے عبرانی میں تراجم
گئے.جبکہ لاطینی میں سب سے پہلے جس شخص نے کی تصنیفات عالیہ سے یوروپ کو روشناس کرایا وہ مائیکل
اسکاٹ (1220) Michael Scott) تھا.وہ سٹی کے شہنشاہ فریڈرک دوم ( قیصر جرمنی) کا درباری مترجم تھا.اس نے سب سے پہلے شرح کتاب السماء و العالم اور شرح مقاله فى الروح کا لاطینی میں ترجمہ کیا.پھر
اس نے مقالہ فی الكون والفساد اور جواہر الکون کے تراجم کئے.لاطینی میں ارسطو کی جن کتابوں کے
مائیکل نے ترجمے کئے وہ یہ ہیں:
De Caelo, De Anima, Physica, Meteorologica, De Generatione Animalum
and Parva Naturalia
اس طرح کی وفات کے صرف پچاس سال بعد یورپ اس کے نام اور کام سے متعارف ہو چکا تھا.مائیکل کے علاوہ ہر مسن دی جرمن (Herman the German) نے بھی ارسطو کی کتابوں اور شرحوں کے
تراجم میں حصہ لیا.راجر بیکن کا کہنا ہے کہ عہد وسطی میں ارسطو ازم کے احیاء کا سراسرذمہ دار مائیکل اسکاٹ تھا.ابن
رشد کی ان شرحوں کے ذریعے یورپ سائنس اور مذہب میں مطابقت جیسے مسائل سے آگاہ ہوا اور وہاں عقلیت
پسندی کی تحریک نے جنم لیا.اس تحریک کے شروع ہونے سے یورپ افلاطون ( ارسطو کے استاد ) کے نظریات کے
طوق سے آزاد ہو گیا.سے پہلے اسلامی ممالک میں مسلمان فلاسفہ (فارابی ، ابن سینا) نے ارسطو کے نظریات کو سمجھنے اور
121
Page 140
بیان کرنے کی کوشش کی مگر بجائے سلجھانے کے انہوں نے ارسطو کے خیالات کو مزید گنجلک بنا دیا.نے یہ
کام کیا کہ اس نے ارسطو کو دوبارہ دریافت کیا، اس کے خیالات کو عمر و رنگ میں بیان کیا ، یہی چیز یورپ والوں نے کی کتابوں کے تراجم سے حاصل کی.چنانچہ پیرس یونیورسٹی، پیڈ وایو نیورسٹی (اٹلی) میں کی کتابیں
نصاب میں شامل تھیں اور اس کے فلسفیانہ خیالات کا مطالعہ خاص طور پر کیا جاتا تھا.کے خیالات اور
نظریات سے ہی یورپ میں کرسچین اسکولیس ٹیزم (Scholasticism) کا آغاز ہوا.یورپ کے علما اور حکما کے لئے کی کتابوں میں حقیقی معنی میں حکمت کے خزانے پوشیدہ تھے.ان کتابوں
کے مطالعے سے وہ نئے نئے تصورات سے متعارف ہوئے جنہوں نے یورپ کے علمی حلقوں میں تہلکہ مچادیا.تیر
ھویں صدی سے لے کر سولہویں صدی تک یورپ کے حکما کے درمیان کے خیالات گرما گرم بحث کا موضوع
بنے رہے، یہاں تک کہ چرچ بھی اپنے اعتقادات بدلنے پر مجبور ہوا.1230 ء کے بعد جب کی کتابیں
یورپ میں مقبول عام ہونے لگیں تو لوگوں نے ان
کا کھلے ہاتھوں استقبال کیا.مگر چرچ کو یہ اچھانہ لگا اور پوپ گریگوری
نم (Pope Gregory IX) نے ایک کمیشن بٹھایا تا کہ اس بات کا فیصلہ کیا جائے کہ کون سی کتابوں کا مطالعہ کیا جا
سکتا ہے.پیرس میں میگر آف برابانٹ (Brabant) اور بوتھیس آف ڈاسیا(Botheius of Dacia ) پر کے شاگرد ہونے کا الزام عائد کیا گیا.اٹلی میں دانت پر کا پیرو ہونے کا الزام لگا کر اس کی وفات کے بعد اس
کی کتاب ڈی مونار کیا (de Monarchia) کو پوپ جان پائیں (Pope John XXII) کے حکم پر نذرآتش کیا
گیا.یادر ہے کہ دانتے نے کو شارح اعظم (che'l gran comento fco) کے خطاب سے نوازا تھا.کی شرحوں نے یہودیوں اور عیسائیوں دونوں اقوام پر زبر دست اثر چھوڑا.اس کا نام بطور اتھارٹی لیا جاتا
تھا اور اس کی رائے سند کبھی جاتی تھی.اہل یہود میں موسیٰ ابن میمون ( 1204ء) اور عیسائیوں میں اٹلی کا ڈومنیکن
راہب، سینٹ ٹامس ایکوئے ناس (1274ء) اور البرٹ دی گریٹ (1280ء ) سے بہت متاثر تھے.كشف عن المناهيج میں نے خدا کی بستی پر اظہار خیال کیا اور اس کے ثبوت پیش کئے.اگر چہ اس کتاب
کالاطینی میں ترجمہ نہیں ہوا تھا مگر اس ایکوئے ناس کی مایہ ناز تخلیق ساتھیولوجی کا (Summa Theologica) میں
جن مسائل پر گفتگو کی گئی وہ ارسطو کے ایسے ملتے جلتے خیالات پر منحصر تھے جو نے پیش کئے تھے.غرضیکہ
عیسائی فلسفہ اور د مینیات پر کے یونانی اور اسلامی نظریات کا اثر گہرا تھا.بقول سر ٹامس آرنلڈ مغرب میں
عیسائیت کی اہم ترین کتاب ایکوئے ناس کی ساتھیولوجی کا میں اسلامی نظریات کی بھر مار اس اعتراض کا صریح توز
ہے کہ مسلم مفکرین میں حقیقی انکار کی کمی تھی.یورپ میں جب ان شرحوں کی تشہیر ہوئی اور لوگوں نے ان کا مطالعہ کیا تو ان پر ارسطو کی بے پایاں حکمت کی
122
Page 141
حقیقت عیاں ہوئی اور انہوں نے افلاطون کی کتابوں کا مطالعہ ترک کر دیا.کے افکار اپنے دور سے بہت آگے
تھے جن کو لوگ ان کی تحریف (sophistication) کی مجہ سے سمجھ نہیں سکتے تھے جس کی واضح مثال نظریہ ارتقا ہے:
His ideas were far too advanced for the world of his time.Thanks to
Averroes the seeds of Renaissance were sown in Europe.کے نظریات کے یورپ پر اثر کی ایک مثال یہ ہے کہ تیرہویں صدی میں لوگوں کا عقیدہ تھا کہ روح
مادی اوصاف سے بری نہیں ہے اور مرنے کے بعد یہ قبر کے گرد و پیش منڈلاتی رہتی ہے.اور یہ کہ روح جہنم میں
جسمانی عذاب میں مبتلا ہو گی.لیکن کے فلسفہ کی بدولت یہ عقیدہ بدل گیا اور لوگ ماننے لگے کہ روح مادہ
سے بالکل الگ جو ہر ہے، اس پر جسمانی عتاب نہیں بلکہ روحانی عذاب ہوگا.کے فلسفہ کی بدولت یوروپ
میں ماہیت روح کے متعلق عامیانہ عقیدوں کے بجائے روح کی اعلیٰ حقیقت کا تخیل پیدا ہوا.ڈیکارٹ
(Descartes) روح کو جسم سے الگ ایک جو ہر ماننے کے عقیدہ کا بانی خیال کیا جاتا ہے حالانکہ اس نے یہ نظریہ سے سیکھا تھا.یورپ میں کیتھولک چرچ نے کو لحد و بے دین تین باتوں کی وجہ سے قرار دیا تھا: عالم کو قدیم تسلیم کرنا
عالم کے حادث ہونے سے انکار، اور تمام ارواح کا اتحاد.یہ الزامات غلط تھے کیونکہ عیسائی یا دریوں کو اس کے
نظریات سمجھنے میں غلط نہی ہوئی تھی.نیز اس کی کتابوں کے تراجم میں سقم تھا.اس نے کیا کہا اور ترجمہ کرنے والے
نے کیا مطلب لیا.یہی چیز شدید غلط انہی کا باعث ہوئی.رینان ہماری رائے سے اتفاق کرتا ہے.ملاحظہ فرمائیں
اس کی رائے : رشدی تحریک ما سواغلط فہمیوں کے سلسلہ کے کچھ بھی نہیں ہے"."The history of Averroeism is nothing but a series of misunderstandings."
عالم قدیم ہے، اس مسئلہ پر ایک لمحہ کے لئے کی رائے پر غور فرمائیں: " عالم قدیم ہے، یعنی اپنے خالق
کے ساتھ اس کو معیت زمانی حاصل ہے اور اگر فرض کرد که صانع عالم اپنی مصنوعات پر یہ انتہار زمانہ مقدم ہو بھی تو
سوال پیدا ہوتا ہے کہ تقدم و تاخر زمانی تو خود زمانیات میں سے ہیں.پس یہ تقدم یا زمانہ میں ہو گا یا زمانہ میں نہ ہوگا.اگر زمانے میں تقدم نہیں ہے تو اس سے لازم آ گیا کہ صانع عالم کو اپنی مصنوعات پر تقدم زمانی حاصل نہیں ہے اور اگر
اس کو تقدم زمانی حاصل ہے تو زمانے کو غیر مخلوق ماننا پڑے گا.غرض اگر ہم یہ مان لیں کہ صانع عالم کوبھی صانع غیر طبعی
کی طرح اپنی معلومات پر تقدم زمانی حاصل ہے تو بعض شکوک پیدا ہوں گے جن کا جواب ناممکن ہے.اس سے معلوم
ہوا کہ مادہ اور صورت دونوں غیر مخلوق اور ازلی ہیں.یعنی خالق عالم ان سے مقدم ہے لیکن زملیا دونوں خالق عالم کے
123
Page 142
:
ہم عصر ہیں." ما بعد الطبعيته مقاله ثالثه )
عہد وسطی کے کیتھولک فلسفہ کا واحد مقصد کے نظریات کا ابطال تھا.اس کے نظریات کا اثر قرون
وسطی اور نشاۃ ثانیہ کے بہت سے مفکرین میں دیکھا جا سکتا ہے جیسے جرمنی کے کارڈینل نمولی آف کو سا ( Nicholas
of Cusa) کو پرٹیکس، جیرارڈ و برونو.یادر ہے کہ برونو پہلا سائنس داں تھا جس نے متعدد تہلکہ خیز نظریات سے
دنیا کو متعارف کرایا تھا جیسے : نہ صرف زمین سورج کے گرد گردش کرتی ہے، بلکہ سورج بھی حرکت کرتا ہے ، یہ کائنات
لا محدود ہے ، ہمارے سیارے کا نظام کائنات مرکز نہیں ہے ، نظام شمسی سے دور ستارے بذات خود ایسے ہم پلہ
نظاموں کے مرکز ہیں.یورپ پر کے نظریات کے اثر کی ایک اور مثال یہ ہے کہ جدید سائنس جس کے بانی بیکن
(Bacon ) ڈیکارٹ (Descartes) گیلیلیو (Galileo) اور نیوٹن (Newton) تھے.ان کے مطابق عالم
کا ئنات مادہ (Matter) اور قوت (Force) کی رزم گاہ ہے اور یہ دونوں ازلی ہیں.قوت کبھی فنا نہیں ہوتی بلکہ
صورتیں بدل لیتی ہے چنانچہ برق اور حرارت اس کی متعدد اشکال ہیں.یہ فلسفہ بھی کے فلسفہ کی آواز
بازگشت ہے جو کائنات کے ازلی و ابدی ہونے پر اصرار کرتا تھا بلکہ اس کو ایک عقل عام کا مظہر بتلاتا تھا اور اسی قوت
سے عالم کی ابتدا ہوئی.علم کیا ہے؟ کے نزدیک علم دو حصوں پر مشتمل ہے: خدائی علم اور انسانی علم.خدا کے علم کا طریقہ یہ
ہے کہ چونکہ خدا کو اپنی ذات کا علم ہے اس لئے جزئیات کا علم اس کا منطقی نتیجہ ہے.ارسطو نے خدا کے علم کو اس کی
ذات کے علم میں بلا شرکت غیر قرار دیا تھا.نے اس نظریے کی سب سے
عمد و تعبیر کی ، وہ یہ کہ خدا چونکہ
جانتا ہے کہ وہ کائنات کا مسبب الاسباب ہے اس لئے جو نتائج اس کی ذات سے نکلتے ہیں وہ اسباب کہلاتے
ہیں.قرون وسطی کے علمی وتعلیمی حلقوں میں یہ تشریح ہر ایک نے تسلیم کی.ٹامس ایکوئے ناس نے اس تعبیر سے
اتفاق کیا اور کہا کہ ارسطو کی بات ٹھیک ہے کہ خدا چونکہ اپنے بارے میں مکمل علم رکھتا ہے اس لئے وہ تمام اشیاء کا
علم رکھتا ہے.(22 Averroes, Majid Fakhri, Oneworld.Oxford, 2001, page)
یورپ میں کے فلسفے پر تین دور گذرے (1) پہلے دور میں کتابوں کے محض ترجمے کئے گئے،
(2) ترجموں کی اشاعت کے بعد دوسرے دور میں کے مقلد پیدا ہوئے جنہوں نے اس کی کتابوں کے حاشیے
اور تفسیر میں لکھیں.چنانچہ پیڈ وا (اٹلی) کے پروفیسروں کا یہی حال تھا (3) اور بعض واقعی اس کے جامد مقلدر ہے.کے فلسفے کا سب سے زیادہ اثر فرانسکن (Franciscan) فرقے پر نظر آتا ہے جس کا صدر مقام
124
Page 143
آکسفورڈ میں تھا.راجر بیکن (Bacon) کا تعلق اسی فرقے سے تھا.اس نے کی تلخیص طبیعیات
(Epitome of Physics)، شرح مقاله فى الروح ، شرح مقاله في السماء والعالم سے بہت سے
اقتباسات اپنی کتاب میں ہو بہو نقل کئے.اس کے برعکس روی نکن (Dominican) فرقہ کے فلسفے کا
سب سے زیادہ مخالف تھا.چنانچہ سینٹ ٹامس ایکوئے ناس (Acquinas) نے اپنی کتاب رد میں
اس پر شدید حملے کئے تھے.اسی طرح ایک عیسائی عالم آرنلڈ آف ویلانووا ( Amold of Vilanova
1240-1311 ء ) نے کی کتابوں کا مطالعہ محض اس لئے کیا تا کہ وہ ان میں غلطیاں تلاش کر سکے.اس نے
افسوس کا اظہار کیا کہ عیسائی فکر و خیال کا انحصار بے دین (مسلمان) عالموں کی تعلیمات پر ہے.کے
نظریات کو رد کرنے کے لئے اس نے اس کے نظریات میں ملاوٹ کر کے ان کو اپنی طرف سے پیش کیا.اور یہودی فضلا
تیرہویں صدی میں مائیکل اسکاٹ نے ارسطو کی جن کتابوں کے تراجم کئے وہ ہیں:
Zoology, Physics, On the Heavens, On Actions and Passions,
Meteorology.On Generation & Corruption
ان تراجم کا لوگوں نے کوئی خاص مطالعہ نہیں کیا لیکن جب یورپ میں یونیورسٹیوں کا آغاز ہوا تو آرٹس کے
نصاب کے لئے انہیں منتخب کیا گیا.مائیکل اسکاٹ ٹولیڈ: (اسپین) سے ہجرت کر کے فریڈرک دوم کے دربار میں گیا
تو وہاں جا کر اس نے کی جن شرحوں کے تراجم کئے ان میں On the Heavens, On the Soul
Physics, Metaphysics شامل ہیں.بادشاہ کے درباری فلسفی تھیوڈور آف انڈیاک ( Theodore of
Antiach) نے کی شرح Proemium to the Physics کا ترجمہ کیا نیز ایک اور درباری ولیم آف
لو (William of Luna) نے Categories, De interpretatione کے ترجمے کئے.عیسائی محققین جب کی عربی میں لکھی کتابوں کے تراجم کرتے تو یہودی فضلا ان کے ترجمان کے
فرائض انجام دیتے تھے.یہ طریقہ چودہویں صدی کے شروع تک مروج رہا جب کالو نے مس بن مائر
(Calonymus ben Meir) نے تهافت التهافة کا ترجمہ نیپلز کے بادشاہ رابرٹ آف انجو ( Robert of
Anjou) کے لئے کیا.تیرہویں صدی کے ختم ہونے سے قبل عربی کتابوں کے لاطینی تراجم عبرانی تراجم سے کئے
جانے لگے کیونکہ یہودی عالموں نے اسپین سے ہجرت کرنے کے بعد یورپ پہنچ کر عربی کے بجائے عبرانی زبان
استعمال کرنی شروع کر دی تھی.اس کا فائدہ یہ ہوا کہ انہوں نے فلسفہ کی متعدد کتابوں کے تراجم عبرانی میں کر دئے.125
Page 144
اس طرح کی 38 تفاسیر اور شرحوں میں سے 15 کے تراجم عبرانی میں ہوئے.ان میں سے اولین ترجمہ سلی
کے بادشاہ فریڈرک دوم کے درباری مترجم جیکب اناطولی نے Die Interpretatione کی شرح متوسط کا کیا.تیرہویں اور چودہویں صدی میں فرانس ، کیلا لونیا اور اٹلی میں جن مترجمین نے یہ فرائض انجام دئے ان میں موسیٰ
ابن طبون Moses ben Tibbon) ، لیوی بن جیرسان (Levi Ben Gerson)، موئی ابن ناربون
Moses ben Narbonne) ، زکریا ابن الحق Zachariah ben Isaac) شامل ہیں.ان عالموں
نے نہ صرف کی شرحوں کے ترجمے کئے بلکہ ان پر اعلیٰ شرحیں لکھیں.History of Islamic)
Philosophy, M.Fakhri, Columbia University Press, NY, 2004, page 285)
پوپ لیور ہم Pope Leo X) اور کا رڈینیل گریمانی (Cardinal Grimani) کی سر پرستی میں نے
تراجم بھی کئے گئے.ان تراجم کی فہرست درج ذیل ہے:
ایلاس ڈیل میڈ میگو (Elias del Medigo)
پالوس اسرائیلیوں (Paulus Israelita)
ابرام ذکی بالمیز (Abram de Balmes)
جو ہانس پورانا (Johannes Burana)
وائی نالس نی سس (Vitalis Nissus)
Metaphysics, Prior Analytics
On the Heavens
Topics.Rhetoric, Poetics
Prior Analytics, Posterior Analytics
On Generation & Corruption
جیکب مان ٹینس (Jacob Mantinus) اس نے کی دس شرحوں کے تراجم از سرنو کئے، اور
افلاطون کی جمہوریہ کا بھی ترجمہ کیا.(1549ء)
قابل ذکر بات یہ ہے کہ 1330ء کے بعد پرنٹنگ پریس کی ایجاد پر پرانے تراجم اور نئے تراجم اکھٹے ایک
جلد میں شائع کئے گئے.1550 ء میں وفیس (اٹلی) میں ارسطو کی کتابوں کے مجموعہ (Corpus) اور کی
شرحوں
کو مکمل سیٹ کی صورت میں شائع کیا گیا.اس کے مزید ایڈیشن 1562ء اور 1573ء میں منظر عام پر آئے.سولہویں صدی میں یورپ کے فضلا میں عربی زبان سیکھنے کا رجحان پیدا ہوا تا کہ دو عربی کتابوں کا مطالعہ براہ
راست کریں.چنانچہ عربی کی صرف و نحو اور لغت غرناطہ کے عالم پید رو الکالہ (Pedro Alcala) نے 1505ء
میں شائع کی.ایک عرب عالم الحسن غرناطی (1485-1554ء، تیونس ) جس کو اغوا کر لیا گیا تھا اور جس کا عیسائی نام
پوپ لیور ہم نے لیو افریکنس (Leo Africanus) رکھ دیا تھا، اس نے 1518ء میں عرب عالموں کی سوانح
عمریوں پر ایک کتاب لکھی.ایک کتاب بنام تھیالوجی آف ارسٹائل (Theology of Aristotle) دمشق میں
126
Page 145
دستیاب ہوئی جو 1519ء میں روم سے شائع ہوئی تھی.اینڈریو الپا گو (Andrew Alpago) نے ابن سینا کی
کتاب القانون کے لاطینی ترجمے پر نظر ثانی کی.1584ء میں عربی پریس روم میں طباعت کے لئے لگا یا گیا جس کا
سر پرست میڈیسی ( Medici) خاندان تھا.یورپ کی یونیورسٹیوں میں عربی کی تعلیم دی جانے لگی اور گیلام پوسل
(G.Postel) نے 1935ء میں پیرس میں یورپ کی سب سے پہلی عرب چیر (Arab Chair ) قائم کی اور
عربی قوائد نحو پر کتاب لکھی.ایڈورڈ پوکاک (Pocock) نے عربی تاریخ پر ایک کتاب سپرد قلم کی.جس میں ممتاز
مسلمان فلاسفہ کے حالات زندگی اور نظریات پیش کئے.اس نے ابن طفیل کے ناول حی ابن یقطان کا ترجمہ کیا
اور اس کے بیٹے نے اس کو عربی متن کے ساتھ شائع کیا.یورپ کی یونیورسٹیوں میں اسلامی فلسفے کے اثر کے تحت
سائمن دین ری ایٹ (Simone van Riet) نے ابن سینا کی کتابوں کے لاطینی تراجم اور کی کتابوں
کے مجموعے (Corpus Averroicum) کو شائع کیا.اور سکیولر ازم
چودہویں صدی کے شروع نصف میں پیڈو یونیورسٹی (اٹلی) کے ممتاز پر دفیسروں نے رشدی تحریک کی شمع کو
لود ینے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی.اس میں فلسفہ اور طلب دونوں موضوعات شامل تھے.ان اساتذہ میں قابل ذکر
نام ہیں: گریگوری آف ریمنی (Gregory of Rimini) جیروم فیراری Jerome Ferari)، جان آف
جندون ( John of Jandun)، ار بانو آف بولونا (Urbano of Bologna)، پیٹر آف ابانو ( Pierre
of Abano).ان نامور اساتذہ میں جان آف جندون (وفات 1328 ء ) سب سے زیاد و ممتاز تھا جس کے دل
میں کے لئے بہت احترام تھا.اس نے کو "صداقت کا نڈر محافظ " خطاب دیا تھا.وہ کائنات کے
قدیم ہونے عقل کل اور شخصی حیات جاودانی کے ناممکن ہونے پر فلسفیانہ طور پر یقین رکھتا تھا.رشدی تحریک میں
سب سے متنازع نظریہ یعنی مادہ کے بغیر کائنات کے تخلیق (ex nihilo) ہونے کو دو نا قابل تسلیم سمجھتا تھا.وہ کہتا
تھا کہ میرے نزدیک خدا ایسا کر سکتا ہے، کس طرح؟ مجھے معلوم نہیں ، صرف خدا ہی جانتا ہے.قرآن حکیم نے اپنے
اعجاز بلاغت سے ex nihilo کا ثبوت اس آیت کریمہ میں پیش کیا ہے.الذی جعـل لـكـم مـن الشجر
الاخضر ناراً فاذا انتم منه توقدون (36:81) (ترجمہ: وہ ایسا قادر ہے کہ ( بعض ) ہرے درخت سے
تمہارے لئے آگ پیدا کر دیتا ہے، پھر تم اس سے مزید آگ سلگاتے ہو.")
جان جندون کا دوست اور رفیق کار مارسیلیس آف پیڈ وا ( Marsilious of Padua 1343ء) تھا.ان
دونوں نے مل کر سیاسیات پر ایک مشہور کتاب بنام امن کا محافظ (Defensor Pacis) لکھی جس میں کے
127
Page 146
سیاسی نظریات بہت زیادہ تھے.مصنف نے کہا کہ عقل اور مذہب کو فلسفیانہ طور پر الگ الگ ہونا چاہئے نیز چرچ اور
اسٹیٹ کو سیاسی سطح پر الگ الگ ہونا چاہئے.یہ نظریہ کی تعلیمات سے اخذ کیا گیا تھا.بعد میں یہ نظریہ یورپ
کے اکثر ممالک میں ان کے آئین کا حصہ بن گیا اور چرچ اور اسٹیٹ کو الگ الگ کر دیا گیا.یہ کی علمی فضیلت کا
مجھے بولتا ثبوت ہے.اس زبر دست تصور (Concept) سے یورپ میں عقلیت پسندی اور انسان دوستی
(Rationalism & Humanism) کی سحر نمودار ہوئی اور اس کی اشاعت سب سے پہلے چودہویں صدی میں
بر پا ہونے والی اطالوی نشاۃ ثانیہ میں کی گئی اور یہ بالآخر رینے ڈیکارٹ (Rene Decartes) کی ریاضیاتی
عقلیت (Mathematical Rationalism) پر منتج ہوئی جسے اب ماڈرن فلاسفی کا بادا آدم تسلیم کیا جاتا
ہے.یہاں ضمناً یہ بتا دینا بھی ضروری ہے کہ اس فکر سے سیکیولر ازم کا آغاز ہوا، اور یورپ کی سیاسی فکر میں ایک نئے سنہری
دور کی شروعات ہوئی.اس سیاسی نظریے سے دانتے ایلی گھیری (1321 ء Dante Alighieri) نے بھی اتفاق کیا تھا.اٹلی کا ممتاز شاعر دانتے ایلی گھیری فلورنس کا رہنے والا تھا.اس نے اپنی شاہکار تصنیف ڈی مونا رکیا
(De Monarchia) میں کے روشن خیال اور نظریہ تعقل ( Theory of Intellect) کو بنیاد بنا
کر ایک نئی سیکولر تھیوری آف اسٹیٹ پیش کی.اس تھیوری کا مقصد پوپ کے اس دعوئی کو چیلنج کرنا تھا کہ ہر بادشاہ مسیح
کے ارضی نائب (پوپ) سے حکومت کے اختیارات حاصل کرتا ہے بجائے خدا کے.دانتے نے کے
نظریے سے اتفاق کیا کہ انسان کا جو ہر (essence ) اس بات میں ہے کہ وہ موجودات کا فہم عقل سے حاصل کرتا
ہے اور یہی وہ چیز ہے جو کسی شخص کو ادنی اور اعلیٰ انسانوں میں ممیز کرتی ہے.تمام انسانوں میں عقل واحدہ
unity of intellect) پر یقین رکھتا تھا جس میں تمام انسانیت شریک ہے.اس زبر دست نظریے سے
دانتے نے یہ منطقی نتیجہ نکالا کہ تمام انسانیت سیاسی طور پر ایک قوم ہے.اس نے مزید کہا کہ پوری انسانیت ایک متحدہ
کمیونٹی ہے جو ارفع مقاصد کے حصول میں کوشاں ہے یعنی آفاقی امن اور ارضی مسرت و آرام.اس کے علاوہ چودہویں صدی میں رشدی تحریک کے جو نامور حامی اٹلی میں گزرے ان کے نام یہ ہیں: پال
آف دیفیس (Paul of Venice) ، پال آف پر گولا (Paul of Pargola) ، نکولس آف فولینو ( Nicholas
of Foligno).پندرہویں صدی میں مائیکل سادانو رولا ( Michael Savonarola)اور پومپا تازی
(1525 Pompanazzi) نے رشدی تحریک کا علم بلند کئے رکھا.سترہویں صدی میں اس تحریک کے بڑے
علمبر دار درج ذیل فضلا تھے: نکولیٹی ( Nicoletti) ، دیر نیاس (Vernias)، نے فس (Niphus) اور ذی مارا
(Zimara ).ان لوگوں نے ارسطو اور کی کتابوں پر خود اپنی زبانوں میں شر میں لکھیں.قابل ذکر بات یہ
ہے کہ ان سب فضلا کے نزدیک ار مطلو کا سب سے مسلمہ شارح تھا.128
Page 147
باب ہفتم
: عصر حاضر میں
جیسا کہ بیان کیا گیا کی شہرت کا پرچم یورپ پر تیرہویں صدی سے لے کر سولہویں صدی تک لہراتا
رہا.اس کے بعد نشاہ ثانیہ کا دور دورہ شروع ہوا اور خود وہاں اس بلند پایہ کے عالم پیدا ہوئے جنہوں نے بنجر یورپی
دماغوں کو سیراب کرنا شروع کیا.انیسویں صدی میں ایک بار پھر یورپ میں کی شخصیت سے دلچسپی پیدا ہوئی
اور انیسویں صدی کو ایج آف ایسٹلائٹینمنٹ (Age of Enlightenment) کہا جانے لگا.بعض لوگوں کا یہ
دعویٰ تھا کہ کے عالمانہ اور فلسفیانہ نظریات کے طفیل اس تحریک کا آغاز ہوا.اس احیائے ثانی میں جن
عالموں نے نمایاں کردار ادا کیا ان کی تفصیل درج ذیل ہے:
ٹامس وان ارپ (Thomas van Erpe)
یورپ کے جس عالم نے سب سے پہلے یہ کہا کہ کی کتابوں کا مطالعہ اصل عربی زبان میں کیا جانا
ضروری ہے، وہ ہالینڈ کا عالم نامس وان ارپ (1584-1624ء) تھا.اس نے خود یورپ کی کسی بھی زبان
میں سب سے پہلے عربی گرامر تصنیف کی.اس نے فلسفہ کے مطالب علموں
کو نصیحت کرتے ہوئے کہا: خوب یا درکھو کہ
ارسطوئے ثانی ( ) کا مطالعہ اس کی اپنی زبان میں بہت بنیادی اہمیت رکھتا ہے.ایم.ہے.مولر (Marcus J.Muller)
جرمن عالم مارکس ہے.مولر 1809-1874ء) پہلا شخص ہے جس نے در حقیقت کا نام صدیوں بعد
لوگوں کے ذہنوں میں تازہ کیا.اس نے تین کتابوں فصل المقال، ضمیمہ اور کشف الادلہ کا ترجمہ ماڈرن
یورپی زبان میں کیا.اس نے یہ ترجمہ اسکور یال میں محفوظ ایک پرانے مخطوطہ کو پیش نظر رکھ کر کیا تھا.1935ء تک ان
تین کتابوں کے تمام ایڈمیشن بشمول ان کے جو عرب دنیا میں شائع ہوئے ، ایم.جے.مولر کے ایڈیشن پر مبنی تھے.129
Page 148
ارنسٹ رینان (Ernst Renan)
یورپ میں سب سے پہلے جس شخص نے کی نہایت عمدہ مستند اور جامع سوانح حیات لکھی وہ فرانس
کا مشہور فلسفی اور تاریخ داں ارنسٹ ریتان (1823-1892 ,Ernst Renan) تھا.جوانی کی عمر میں وہ
پادری بننا چاہتا تھا اس لئے ساربون (Sorbonne) کی تمیزی (Seminary ) میں اس نے تعلیم حاصل
کی.1849ء میں اس کو ایک سائنسی مشن پر اٹلی بھیجا گیا.اگلے سال اس کا تقرر پیرس کی نیشنل لائبریری میں لا
ئبریرین کے بطور ہوا.کی زندگی پر 1852ء میں اس نے پی ایچ ڈی کا مقالہ لکھا جس کا عنوان تھا
'Averroes et l'Averroism" - 1860ء 1ء میں اس کو مشرق کے اسلامی ممالک میں خاص مشن پر
بھیجا گیا ، اس طرح اس کو مشرقی زبانوں اور مذاہب کے تقابلی مطالعے کا موقعہ ملا.1862ء میں اس کا تقرر عبرانی
زبان کے پروفیسر کی حیثیت سے پیرس میں ہوا.اس نے کئی کتابیں لکھیں جن میں ایک اہم کتاب ہسٹری آف
کر کمیٹی (History of Christianity) ہے.رینان کی مصنفہ کی سوانح عمری کی اشاعت کے بعد عربوں کو بھولا ہوا یاد آیا.چنانچہ اس کے
بعد کی سوانح عمریاں عربی میں منصہ شہود پر آنا شروع ہوئیں اور اب تک درجنوں کتا میں شائع ہو چکی ہیں.عہد حاضر میں شائع ہونے والی اور کی یاد کو زندہ رکھنے والی ان جدید کتابوں کی فہرست اس باب کے آخر میں
دی جارہی ہے.ان کتابوں کے مطالعے سے اس بات کا اعادہ ہوتا ہے کہ انسان تو مر جاتا ہے مگر نظریات کبھی نہیں
مرتے.کی کتابیں قرطبہ میں جلائی گئیں مگر ان کے نظریات ان کتابوں کے جلنے سے راکھ نہیں ہوئے.ابن
رشد اب بھی دلوں اور دماغوں پر حکومت کر رہا ہے.جب ایک دفعہ کوئی نظریہ جڑ پکڑلے تو پھر اس کے درخت بننے
میں کوئی رکاوٹ کام نہیں آتی.رینان نے کے فلسفے کا سارا علم لاطینی اور عبرانی کتابوں کے ترجموں سے حاصل کیا تھا.اس نے کی سوانح عمری کے لئے ابن الا بار، الا انصاری، ابن ابی اصیحہ الذہبی کی لکھی ہوئی سوانح عمریوں کو پیش
نظر رکھ کر ان کا تنقیدی جائزہ پیش کیا.چنانچہ ارنسٹ رینان نے جس طریقہ سے کی تصویر پیش کی وہی
اسلامی دنیا میں قابل قبول کبھی گئی.اس تصویر میں اب تک کوئی اور عالم رنگ نہیں بھر سکا.مثلا رینان نے کہا کہ
اسلامی دنیا میں انحطاط کی وفات (1198ء) کے بعد شروع ہوا.یہ انحطاط انیسویں صدی میں اسلامی
نشاة ثانیہ (Renaissance) کی سحر طلوع ہونے تک قائم رہا.یہ نشاۃ ثانیہ یورپی نظریات کے اسلامی دنیا میں
فروغ سے شروع ہوئی.بقول رینان کی وفات کے بعد مسلمانوں میں اگلے چھ سو سال کے لئے
130
Page 149
آزادی فکر (Free Thought) ختم ہوگئی اور مذہب کی غلط ترجمانی شروع ہوگئی.1198ء میں چھ سو سال جمع
کرنے پر تاریخ 1798 بنتی ہے جب فرانس نے نپولین کی قیادت میں مصر پر قبضہ کر لیا.رینان کا دعوی ہے کہ
نپولین کے مصر میں آنے سے اسلامی دنیا میں جدیدیت (Modernity) کا آغاز ہوا.یورو چین مورخ اس چھ
سوسال کے عرصے کو اسلامی دنیا کا تاریک دور (Dark Age) خیال کرتے ہیں لیکن ہم اس سے اتفاق نہیں
کرتے کیونکہ اس عرصہ میں ہندوستان میں مغل حکومت اور ترکی میں سلطنت عثمانیہ نے جو کارنامے سرانجام دئے
وہ اپنی جگہ قابل قدر ہیں.رینان نے کی وفات کی تاریخ کو اسلامی دنیا کے ذہنی اور علمی زوال کا نقطہ آغاز قرار دیا تو
مشرق و مغرب میں اس نقطہ نظر کو اس قدر قبولیت حاصل ہوئی کہ گویا یہ خیال فیشن بن گیا.ایک اور مصنف کو گل من
(Kugelgen) کے مطابق کی موت ( تاریخی نقطۂ نظر سے ) مغربی اور اسلامی تعقل کی تاریخ کے لئے
نقطه انقلاب ( Turning Point) بن جاتی ہے.یورپی کلچر کے عروج کی علامت اور اس.بے اعتنائی اسلامی کلچر کازوال ہے.وہ کہتا ہے."Averroes' death becomes the turning point for European as well as
Islamic intellectual history.Averroes becomes the symbol of the rise of
European culture; to neglect him stands for the downfall of Islamic
culture." (56)
یہ قابل ذکر ہے کہ جمال الدین افغانی اور رینان کے درمیان خط و کتابت کا سلسلہ رہا.قاہرہ یونیورسٹی میں
رینان کی یاد میں ایک اجلاس 1923ء میں منعقد ہوا تھا.میکس ہورٹن (Max Horton)
میکس ہورٹن (1874-1945ء) نے اپنی ساری زندگی اسلامی فلسفہ کے مطالعے میں گزاری.اس نے
فارابی، ابن سینا، رازی شیرازی، طوق، رشید رضا اور محمد عبدہ کی زندگیوں کا مطالعہ کیا.ابن سینا کے بعد اس نے ابن
رشد کی زندگی پر بہت کچھ لکھا مثلاً تهافت النحافة کا اس نے جرمنی میں خلاصہ تیار کیا نیز کی میٹا فزکس پر
کتاب
لکھی.اس کے نزدیک اسلام اور قرآن کا دلائل سے ثابت کر نے والا سب سے بڑ ادائی
Apologist for Islam & Quran) تھا.131
Page 150
ارنسٹ بلاک (Ernst Bloch)
ارنسٹ بلاک (1885-1977 ء ) ممتاز جرمن فلسفی تھا اس نے ابن سینا اور کے فلسفیانہ خیالات کو
اپنے فلسفے کا حصہ بنایا.سولہ سال تک تو بنگن (Tubingen) یونیورسٹی (جرمنی) میں پروفیسر رہا.اس کے نزدیک
ابن سینا، ابن طفیل اور نے سیکولر نظام کو مذہبی نظام سے الگ کر کے مذہب اور فلسفے میں امتیازی فرق بیان
کیا.اس کے نزدیک ابن سینا اور وحدت الوجودی تھے.مذہب کے طوق سے چھٹکارا حاصل کرنے کے
لئے وحدت الوجود کا عقیدہ بنیادی شرط ہے.وہ کہتا تھا کہ ابن سینا اور نیچر لسٹ (Naturalist) بھی تھے.ہر مسن لے (Herman Ley)
ہر سن لے (پیدائش 1911 ء ) مشرقی جرمنی میں عہد وسطی کے فلسفے پر سند تسلیم کیا جاتا تھا.وہ کے
خیالات سے بہت متاثر تھا.شام کے دو محقق طیب تازینی اور نیف بالوز بھی اس کے خیالات سے متاثر تھے.جرمنی ہی
کے فلسفی فریڈرک اینجلز نے کہا تھا کہ عربوں کا لائف سینٹرڈ فری تھاٹ (Life Centerod Free Thought)
روم کے لوگوں سے بہت اعلیٰ تھا جس کی بناء پر مادیت اور مارکسزم کا آغاز ہوا.ایک سوویت محقق اے.وی.گاریف (A.Saghadeer) نے کی سوارغ پر کتاب لکھی اور کہا کہ کی تعلیمات سے ارسطو
کی تعلیمات مادہ پرستی میں منتقل ہو گئیں.اس کا ذکر گریٹ سوویت انسائیکلو پیڈیا میں بھی کیا گیا.تا ہم ایک اور محقق
نے کہا ہے کہ فارابی، ابن سینا ، غزالی اور نے اپنے فلسفے اور سائنس کا علم اسلام کے دفاع میں استعمال کیا.ہمارے دور میں
تیرہویں صدی سے لے کر سترہویں صدی کے نصف اول تک یورپ کے محققین ارسطو کی کتابیں کی
تفاسیر کے ساتھ پڑھتے تھے.اٹلی کے نامور مصور رافیل (Raphael) نے پلاسٹر کے اوپر ایک پینٹنگ بنائی جس کا نام
وی اسکول آف ایتھنز (151011ء) ہے.یہ وٹیکن (اٹلی) کے سٹیلا ڈیلا سکنا نورا (Stella della Segnatura)
میں رکھی ہوئی ہے.اس پینٹنگ میں کو فیا غورث کے پیچھے اس کے کندھوں کے اوپر سے دیکھتے ہوئے پیش کیا
گیا ہے.مصر کے فلم ڈائر یکٹر یوسف شاہین نے 1997ء میں ایک فلم ڈیس نینی ( Destiny) بنائی جس میں بنیاد
پرستی سے پیدا ہونے والے خطرات سے آگاہ کیا گیا تھا.یہ فلم انہوں نے کی زندگی سے متاثر ہو کر بنائی تھی.132
Page 151
کی زندگی پر انہوں نے جو فلم بنائی اس کا نام فیٹ (Fate ) تھا.اس میں کے سنہری کارناموں کو
اجاگر کیا گیا ہے.ارجینا (جنوبی امریکہ ) کے ادیب جورگ لوئیس بورگز ( Borges) نے ایک مختصر کہانی لکھی جس کا نام
ایوروس سرچ (Averroes Search) ہے.اس میں کو اپنی لائبریری میں مصروف لفظ ٹریجڈی اور
کامیڈی کے معمے کو حل کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے.اس کہانی کا پس منظر یہ ہے کہ رینان نے اپنی کتاب میں لکھا تھا
کہ نے کتاب الشعر (Poetics) کی جو تشخیص لکھی ہے اس کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو یونانی
لٹریچر کا علم بہت کم تھا.وہ ٹریجڈی اور کامیڈی میں فرق کو نہیں جان سکا، اس لئے ان کی مثالیں عربی ادب ( مدحیہ اور
طنزیہ نظموں) بلکہ قرآن مجید میں تلاش کرنے کی بے سود کوشش کرتا رہا.کا مجسمہ قرطبہ کے پرانے حصے میں موجود ہے.یہ مجسمہ سنگ تراشی کا نادر شاہ کار ہے.بائیں ہاتھ میں
اس نے کتاب پکڑ رکھی ہے اور اس کو اٹھنے کے انداز میں دکھایا گیا ہے گویا کسی مہمان کے استقبال کے لئے اٹھا ہے.اس کے جوتے نوک دار ہیں ، خوبصورت داڑھی تراشی ہوتی ہے.اس طرح باری لونا (Barcelona) یو نیورسٹی
کے گر جا کے پیش دالان میں بھی اس کا ایک مجسمہ لگا ہوا ہے.قرطبہ میں ایک تھری اسٹار شاندار ہوٹل کا نام ہوٹل
ایور دس ہے.قرطبہ کے ایک میوزیم میں اس کی موم سے بنی قد آدم تصویر (wax figure ) موجود ہے.فیض
(مراقش) میں ایک ابتدائی اسکول کا نام ہے.شکاگو (امریکہ ) میں ایک اسلامی اسکول (ایورویس
اکیڈیمی ) گزشتہ پانچ سال سے بچوں کو ابتدائی تعلیم دینے میں مصروف کار ہے.چاند کا ایک فرضی ٹکڑا کے
نام سے منسوب کیا گیا ہے جس کا عرض بلد 11.75 اور طول بلد 21.7E اور اس کا قطر 32 میل کا ہے.منوع
(سعودی عرب ) میں ایک کیمیکل پلانٹ کا نام پلانٹ ہے.جرمنی سے کی یاد میں ایک انعام پر ائز فار فری ڈم آف تھاٹ (مؤسسه للفكر الحر ) کی آٹھ سو سالہ وفات کے تین دن یعنی دس دسمبر 1998 ء کو برلن میں شروع کیا گیا تھا.1999ء میں یہ انعام الجزیرہ ٹیلی ویژن کو عرب ممالک میں آزادی تقریر کی اشاعت کرنے پر دیا گیا.اس کا نصب
العین اندسی فلسفی کے نظریات خاص طور پر آزادی کرائے کو اجاگر کرنا ہے.اس انعام کے لئے ایسے کسی
عرب محقق مرد یا عورت کا نام پیش کیا جا سکتا ہے جس نے اسلامی فکر کی اصلاح میں بنیادی کام کیا ہو اور جو اسلامی
روایت اور جدید ذہن میں مفاہمت پیدا کرنا چاہتا ہو.اور اس کے علمی کارناموں نے عرب دنیا میں فوری اثر مرتب
کیا ہو.اس انعام کی تفصیل اس ای میل پر بھیجی جاسکتی ہے.info@ibn-rushd.org.اس کی ویب سائٹ
کا پتہ ہے www.ibn-rushd.org
133
Page 152
کوئیز یو نیورسٹی کے کیٹیلاگ میں مائیکر فلم (884:5 EEB) پر موجود اور یونان کے ایک لائق
ترین میٹرو ڈورس (Metrodorus) کے درمیان خط و کتابت کا علم ہونے پر خوشی کی انتہا نہ رہی.دونوں میں یہ
خط و کتابت 1149-1150ء میں ہوئی تھی.اس خط و کتابت کو لندن کی ٹی سول کمپنی نے 1695ء میں
کتابی شکل
میں لندن سے شائع کیا تھا اور یونیورسٹی مائیکر د فلم (این آر بر مشی گن ، امریکہ ) نے اس کو 1976ء میں مائیکر و فلم پر
محفوظ کیا تھا.میں صرف اس کا پہلا صفحہ پڑھ سکا جس کا عنوان ہے:
Being a Transcript of several letters from Averroes, an Arabian
Philosopher at Corduba in Spain, to Metrodorus, a Young Grecian
Nobleman.student at Athens, in the Years 1149 and 1150.مانگر فلم کی فوٹو کاپی بھی حاصل کی مگر پڑھنے کے قابل نہ تھی ، کاش میں اس مکمل خط و کتابت کو پڑھ سکتا جو دونوں کے
درمیان طب کے مسائل پر ہوئی تھی.میں نے یو نیورسٹی مائیکر فلم کوخط لکھا کہ اگر ان کے پاس اچھی کاپی ہو تو مجھے اس
کی فوٹو کاپیاں بھجوائیں، اگر کسی نے میری درخواست کو درخور اعتنانہ سمجھا.کاش میرے بعد کوئی اور اس خط و کتابت کو
انگریزی سے اردو میں ترجمہ کر کے شائع کر سکے.اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو (UNESCO) کے ڈائریکٹر جنرل ایف میر ( F.Mayor) اور ہالینڈ کے
سیکرٹری آف ایجو کیشن نے 25 جنوری 1997ء کو ایوروس فاؤنڈیشن ٹریننگ سینٹر کا افتتاح ایمسٹرڈم میں کیا.ایور دس
سینٹر کو بچوں کے والدین ، صوبائی حکومت اور لوکل گورنمنٹ آپس میں مل کر چلائیں گے.1978ء میں الجزائر میں پر منعقدہ عالمی تقریب کے موقعے پر شام (Syria) نے اس کی یاد میں ایک ڈاک ٹکٹ جاری کیا تھا.یہ ڈاک
ٹکٹ ابن سینا اکیڈمی علی گڑھ میں موجود ہے.مزید براں فارابی، البیرونی، ابن الہیشم، رازی اور دوسرے مسلم سائنس
دانوں کے علاوہ ابن سینا پر جاری کردہ 35 سے زیادہ ڈاک ٹکٹ ابن سینا اکیڈمی کی زینت ہیں.جون 1998 ء میں فرانس کی سوربون یونیورسٹی (Sorbonne University ) میں کی آٹھویں
صد سالہ برسی پورے جوش و خروش کے ساتھ منائی گئی.اس موقعے پر مصر کے فلم ڈائریکٹر یوسف شماہین کی فلم فیٹ
(Fate) دکھائی گئی.اکتوبر 1998ء میں قرطبہ میں بھی کی 800 سالہ برسی بڑے اہتمام کے ساتھ منائی
گئی.صوبہ اندلس کی وزارت فرہنگ و ثقافت کے مشیر نے اس موقعے پر کہا کہ موجودہ زمانے میں اگر کے
رہے کے انسان پیدا ہوتے تو ہم ہر قسم کے تشدد اور انتہا پسندی کا مقابلہ بخوبی کر سکتے تھے.اس موقعے پر کی
زندگی پر تین کتابیں شائع کی گئیں.ایک کتاب میں کی کتابوں سے اقتباسات پیش کئے گئے ہیں.یہ کتاب
134
Page 153
اندلس کے سیکنڈری اسکولوں میں تقسیم کی جائے گی.اشبیلیہ اور مالاگا میں بھی ایسی کا نفرنسیں منعقد ہوئیں.اشبیلیہ کی
کا نفرنس کے لئے مراقش.ولی عہد سدی محمد نے اپنے پیغام میں کہا کہ کی زندگی ہمیں جو سکھلاتی ہے اس
کا ماحصل ہے: "ذہبی زندگی کے ساتھ رواداری اور برداشت کا مادہ".اس آٹھ سو سالہ بری کے موقعے پر مراتش
اسپین اور پرتگال سے لائے گئے نوادرات کی نمائش بھی کی گئی تھی.قاہرہ میں ایک سوسائٹی کا نام ایوروس اینڈ اسلائنمنٹ ایسوسی ایشن ( Averroes and
Enlightenment Association) ہے.اس کے جملہ مقاصد میں سے تین اہم مقاصد درج ذیل
ہیں.عقلیت عورتوں کے حقوق اور عالم اسلام میں اوپن سوسائٹی.جون 2004ء میں ابوظہبی میں ایک کانفرنس
اس ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام منعقد ہوئی جس کا عنوان تھا:
"Rationality as a Bridge Between East and West"
پرنس چارلس اور آج سے دس سال قبل برطانیہ کے پرنس چارلس، دی پرنس آف ویلز نے اسلام اینڈ دی ویسٹ' کے عنوان پر
تقریر کی اور کہا: " اسپین میں آٹھ سو سالہ اسلامی تہذیب اور حکومت (آٹھویں صدی سے لے کر پندرہویں صدی
تیک) کی اہمیت کو جانے میں ہم نے غلطی کی ہے.کلاسیکل کتابوں کے بچانے اور نشاۃ ثانیہ کے شروع ہونے میں
اسلامی اسپین نے جو حصہ ادا کیا ہے، اسے سب تسلیم کر چکے ہیں.نہ صرف اسلامی اسپین نے پرانی یونانی کتابوں اور
رومن تہذیب کے علمی وفکری کاموں
کو محفوظ کیا بلکہ ان کی کتابوں کی تفاسیر لکھ کر ان کی تہذیب کو مزید وسعت دی.اس طرح انہوں نے سائنس، بیست، ریاضی، قانون ، تاریخ، طب، علم الادویہ علم المناظر علم الفلاحت ، دینیات
موسیقی میں اہم خدمات انجام دیں.اور ابن زہر نے اپنے پیش رو عالموں محمد بن زکریا رازی اور ابن سینا کی
طرح طلب کے مطالعہ و تحقیق کو جس طرح ترقی دی، اس سے صدیوں بعد یورپ نے استفادہ کیا."
"Averroes is designated as a symbol of rationalism."
135
Page 154
مآخذ و مصادر
ذیل میں کی حیات اور کارناموں پر مشتمل ان کتابوں کی فہرست پیش کی جارہی ہے جو موجود و زمانے
میں دستیاب ہیں.عربی زبان میں کتابیں:
بداية المجتهد و نهاية المقتصد ، مرتبه عبد الموجود، بیروت، 1996ء
2 فصل المقال ، مرتبه عبد النادر، بیروت 1961ء
جوامع كون الفساد ( رسائل - جوامع السماء الطبعی ) مرتبہ M.Puig ، میڈرڈ 1983ء
4 الكشف المناهيج الادله ، مرتبہ ایم قاسم، قاہرہ، 1961ء
-3- كتاب السماء الطبعي ( جوامع ) مرتبہ J.Puig ، میڈرڈ 1983ء
-6- الكليات فى الطب ، مرتبہ الیس شیبان اور الطالبی، قاہرہ ، 1989ء
-7
رسائل ، دائرة المعارف حیدرآباد 1947ء
8- رسائل الطبيه ، مرتبہ جی ایس انا داتی ، قاہر 1987ء
رسالة الاتصال بالعقل الفاعل ، مرتبه الاحواني
10- تفسير ما بعد الطبيعة ، مرتبہ M.Bolyges ، بیروت 1952-1938ء
11 تهافت التهافت ، مرتب M.Bouyges ، بیروت 1930ء
12- تلخيص كتاب الحس والمحسوس، مرتب M.Blumberg ، کیمبرج، میسا چوسٹس امریکہ 1972ء
13- تلخيص كتاب الكون والفساد.مرتب S.Kurland کیمبرج ، میسا چوسٹس 1958 ء
-14- تلخيص كتاب الخطايه مرتبه، ایم ایس سلیم قاہرہ 1971ء
15- تلخيص كتاب الماكولات ، مرتبہ، M.Bouyges ، بیروت 1932ء
16- تلخیص کتاب النفس ، مرتب G.Nogales، میڈرڈ 1985ء
17- تلخيص كتاب الشعر مرتبہ چارلس بڑورتھ C.Butterworth،قاہرہ 1986ء
18- تلخيص (جوامع ) كتاب ما بعد الطبيعه ، مرتبه عثمان امین قاہرہ 1958ء
19- تلخيص متعلق ارسطو، مرتبه G.Jihani برات 1982.136
Page 155
20 الطبيب، دار المعارف قاہر: 1953ء
21 مصادر جديده عن تاريخ الطب عند العرب 1959ء
22- و فلسفته ، فرح انطون ، مدیر الجامعه (ربنان کی کتاب کا نامکمل خلاصہ ) دار الفارابی ،
بیروت 1988ء
-23 فلاسفة الاسلام في المشرق والمغرب محمد لطفى جمعه
-24 كتاب الآثار الادهار - (اسے بیروت کے دو عالموں نے مشاہیر عرب کے حالات میں لکھا ہے اور کا مفصل ذکر کیا ہے )
-25 من الكندي الى ، موسى الموسى ، بیروت 1982ء
26 في فلسفة الوجود والخلود محمد عبد الرحمن بیمار، دارالکتاب اللبنانی بیروت 1973ء
27- ، فیلسفوف قرطبه، ماجد فخری بیروت 1960ء
-28 مؤتمر الذكره الماويه الثمينه لوفاته Nov 1978 giers - الموسه
الوطنية الفنون الطبعيته 1985ء
29- الفيلسوف محمد یوسف موسی، داراحياء الكوب العربيه, قاهر : 1945ء
آکسفورڈ یونیورسٹی کی لائبریری میں پر موجود کتا ہیں:
30 عباس محمود عقاد،(1964-1889)، ، دائر والمعارف قاہرہ 1955ء
31 کامل محمد عمویدا ، اندلسي فيلسفوف العرب والمسلمون، دار الكتب العلمیہ بیروت 1993ء
32 یوحنا میر ، والغزالی، دار المشرق بيروت - 1969ء
33- محمد عرے لبی ، و فلسفة الاسلام، دار اشكر اللبنانی بیروت 1992.34 محمود قاسم و فلسفة الدينيه ، كتب المصريه قاهره 1969ء
اردو میں:
1- از نواب عماد الملک مولوی سید حسین بلگرامی اردو زبان میں پہلا مضمون جو ان کے مجموعہ مضامین
میں شامل ہے.2 از شبلی نعمانی الندوہ میں شائع ہونے والا طویل مضمون.از ارنسٹ رینان فرانسیسی سے اردو ترجمہ از معشوق حسین خاں.137
Page 156
4 دارالترجمہ جامعہ عثمانیہ حیدر آباد 1929ء
5 از عبد الواحد خال (لائبریری آف کانگریس ) ، 320 صفحات
6 از محمد یونس فرنگی محل، اعظم گڑھ، 1922 ۱۳۴۲/۶
حکم ہے اسلام حصہ دوم زمولا نا عبد السلام ندوی مطبع معارف اعظم گڑھ ( سو صفحات پر مشتمل کے
حالات زندگی )1956ء
انگریزی میں:
1.Earnst Renan - Ibn Rushd, Translated from French into English,
Darut Tarjuma.Jamia Osmania, Hyderabad, 1922
2.Roger Arnaldez, Averroes - A rationalist in Islam.Notre Dame,
Indiana
3.Majid Fakhri, Islamic Philosophy, Theology, and Mysticism,
Oxford 1997
4.Ibrahim Najjar, Faith and Reason in Islam, Ibn Rushd, Oxford
2001
5.E.Rosenthal, Commentary on Plato's Republic, Averroes,
Cambrdige 1956 Rosenthal
6.Simon Von Den Bergh.The Incoherence of the incoherence
translated, Oxford U.P.1954
7.Oliver Leaman, Averroes and his Philosophy, Oxford, Clarendon
Press, 1988
8.M.C.Hernandez, Ibn Rushed, London, 1997
9.Dominique Urvoy, Ibn Rushd, American University in Cairo Press,
Cairo, 1991
10.S.H.Nasr, History of Islamic Philosophy, Routledge, London, 1996
138
Page 157
فرانسیسی میں:
1.S.Munk, Melanges des philosophie juive et arabe.A.Franck,
Paris, 1859
2.Corbin, H., Histoire de la philosophie ilsamique, Paris, Gallimard,
1964
3.Gauthier, L., Ibn Roshd (Averroes), Paris, Presses Universitaires
de France, 1948
جرمن میں:
1.De Boer, T.J., Geschichte der Philosophie in Islam.Stuttgart,
Frommanns Verlag.1901 Translated into English by E.R.Jones, London,
Luzac, 1903
139
1
Page 158
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.References
Nadvi, A.S.Renan page 39, Hukamae Islam (Urdu), A.S.Nadvi, page 106.Sarton, G.History of Science, G.Sarton, Vol II, page 250.Arnaldez, R., Averroes - Notre Dame, Indiana, USA, page
149.Nadvi, A.S., Hukamae Islam, Vol.II, page 110.Sarton, G., History of Science, Vol II, Baltimore, USA,
1931, pp 230-233.Austin, R WJ., Sufis of Andulasia, Beshara Publications,
1988, page 23.Watt, W.M., History of Islamic Spain, Edinburgh Univ.Press, 1965, page 109.Rosenthal, E.J., Averroes' Commentary on Plato's
Republic, Cambridge Univ.Press, 1956, page 166.Read Jan, Moors in Spain & Portugal, Rowman &
Littlefield, NY 1975, p.75.Conde J A, History of Arabis in Spain, London, Vol.3,
1854, page 15.Arnold, T.W., Legacy of Islam, Oxford University Press,
1931, page 275.Sarton, G., History of Science, Vol.2, page 286.Arnaldez, R.Averroes.University Notre Dame, Indiana,
USA, page 12.Watt, W.M., History of Islamic Spain.1965, page 135.Peters, Rudoph, Jihad in Medieval and Modern Islam,
Chapter on Jihad from Bidayatul Mujtahid, E.J.Brill,
Leiden, 1977, page 11.Musannifin, Idara-tul (Urdu), Hidayatul Muqtasid, Part
of Bidaya, Jhang Pakistan, 1958, pp.30-31.Sarton, G., History of Science, pp.305-306.Arnaldez, R., Averroes- A Rationalist in Islam, pp.26-28.Dictionary of Scientific Biography, Vol.12.Article Ibn
Rushd.Neuberger History of Medicine, Vol.I.1910, page 383.
Page 159
21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.Riesman, D., History of Medicine.Paul Hoeber, NY 1935,
pp.61-62.Sabra, A.I..Science in Islam.MIT Press, London.UK.Page 351.Journal of the History of Medicine, #24, 1969, pp 77-82.Farangi Mahal M.Younus, Ibn Rushd.Azamgarh, 1952,
page 109.Fletcher, R, Moorish Spain, H.Holt, NY 1992, page 75.DSB, Vol.12
Toomer, G., Almagest, Gerald Duckworth & Co., London,
1984, page 41.Nallino, C.A., Arabian Astronomy during medieval times,
(Arabic) Rome 1911, page 22.Saliba, George, History of Arabic Astronomy.NY
University Press, 1994, page 22.ibid, page 63.Ibid, page 69.Glick, Thomas, Convivencia, G.Braziller, NY, 1992, page
93.Wahba, Mourad, Averroes and the Englightenment,
Promtheus Books, NY, 1996, page 49.Rescher, N, Studies in Arabic Philosophy.University of
Pittsburgh Press, 1966, p.153.Sarton, G, History of Science, Vol.II.page 357.Singer, Charles, Short History of Ideas to 1900, Clarendon
Press, Oxford 1959, p.155.Fakhri, Majid, Averroes, Oneworld, Oxford, 2001,
50.page
Asimov, I.Biographical Encyclopedia.Doubleday.NY,
1982, page 89.Butterworth, C E, Introduction of Arabic Philosophy into
Europe, EJ Brill, NY 1994, p.20.Barq, G.Jilani, Falsafian-e-Islam (Urdu), Sh.Ghulam Ali
Sons, Lahore 1968, p.46.Arnold, T.W., Legacy of Islam.Oxford Univ.Press, 1968,
page 275.Arnold, Legacy of Islam, page 276.141
Page 160
43.Goldstein, T., Dawn of Modern Science, Houghton
44.45.46.47.48.49.50.51.52.53.54.55.Company, Boston, 1980, p.113.Arnold, Legacy of Islam, page 276.Fakhri, M., Islamic Philosophy, Theology & Mysticism,
Oneworld, Oxford, 1997, p.95.Arnaldez, R, Averroes, Indiana University, USA, 2000, p.115.Azimabadi, Great Personalities in Islam, Adam Publishers,
Delhi, 1998, p.173.Encyclopedia of Islam, Vol.I, page 737.Nasir, Dr.Naseer.Sarguzisht-e-Falsafa, Feroz Sons,
Lahore, 1991, page 428.ibid, pp.444-448.Hoodbhoy, Dr.P., Islam and Science, Zed Books, NJ,
1991, p.114.Nadvi, A.S., Hukamae Islam, Azamgarh, 1953, pp.345-
348.Sarton, G., History of Science, Vol.2, p.287.Schmitt, C.B., Aristotle and the Renaissance, Harvard
Univ.Press, Cambridge, USA, 1983, page 23.Fakhri, M., Averroes, Oneworld, Oxford, 2001, p.22.56.Wahba, M., Averroes & Enlightenment, NY 1966, p.160.142
Page 161
مصنف کا تعارف
محمد زکر یا ورک گورداسپور، ہندوستان میں 28 جون 1946 ء کو پیدا ہوئے.کراچی سے قانون کی ڈگری
حاصل کرنے کے بعد 1971 ء میں اعلیٰ تعلیم کے لئے جرمنی کی قدیم شہرہ آفاق یو نیورسٹی کو تھنکن گئے.1973ء
سے کینیڈا میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ مقیم ہیں.زکریا
زکر یا درک گزشتہ میں سال سے کینیڈا میں اردو ادب کے فروغ کے سلسلے میں کوشاں ہیں.ان کی نگارشات
کینیڈا، ہندوستان ، برطانیہ، امریکہ اور پاکستان کے موقر جرائد اور اخبارات کی زینت بن چکی ہیں.بطور مترجم وہ
دو کتابیں انگریزی سے اردو میں اور بطور مؤلف نوبل انعام یافتہ سائنس داں ڈاکٹر عبد السلام کی عہد آفریں زندگی پر
دو کتابیں تالیف کر چکے ہیں.پاکستان اور ہندوستان میں ان کو مقابلہ ہائے مضمون نویسی میں متعدد انعامات مل چکے
ہیں.1996ء میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے مجلہ تہذیب الاخلاق کے مقابلہ مضمون نویسی قوموں کے عروج و
زوال میں سائنس اور ٹیکنالوجی کا کردار میں ان کو پہلا انعام دیا گیا تھا.اردو، عربی ، جرمن اور انگریزی زبانوں پر
ان کو عبور حاصل ہے.اسلام اور سائنس' کے موضوع پر ان کے دو درجن سے زیادہ مضامین شائع ہو چکے ہیں.1997ء میں حرمین شریفین کی زیارت کے بعد ان کو پاکستان اور ہندوستان کی سیاحت کا موقعہ ملا.سیر و سیاحت کے علاوہ مطالعے کے بہت شوقین ہیں.کینیڈا کے صوبہ اونٹاریو کی وزارت صحت کے کمپیوٹر
زیارٹمنٹ سے عنقریب ریٹائرمنٹ کے بعد وہ کینیڈا میں اردو ادب کی تاریخ قلم بند کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں.اس
سے قبل مارچ 2005ء میں ان کی کتاب 'مسلمانوں کے سائنسی کارنامے' مرکز فروغ سائنس کے زیر انتظام
شائع ہو چکی ہے.zakariav@hotmail.com