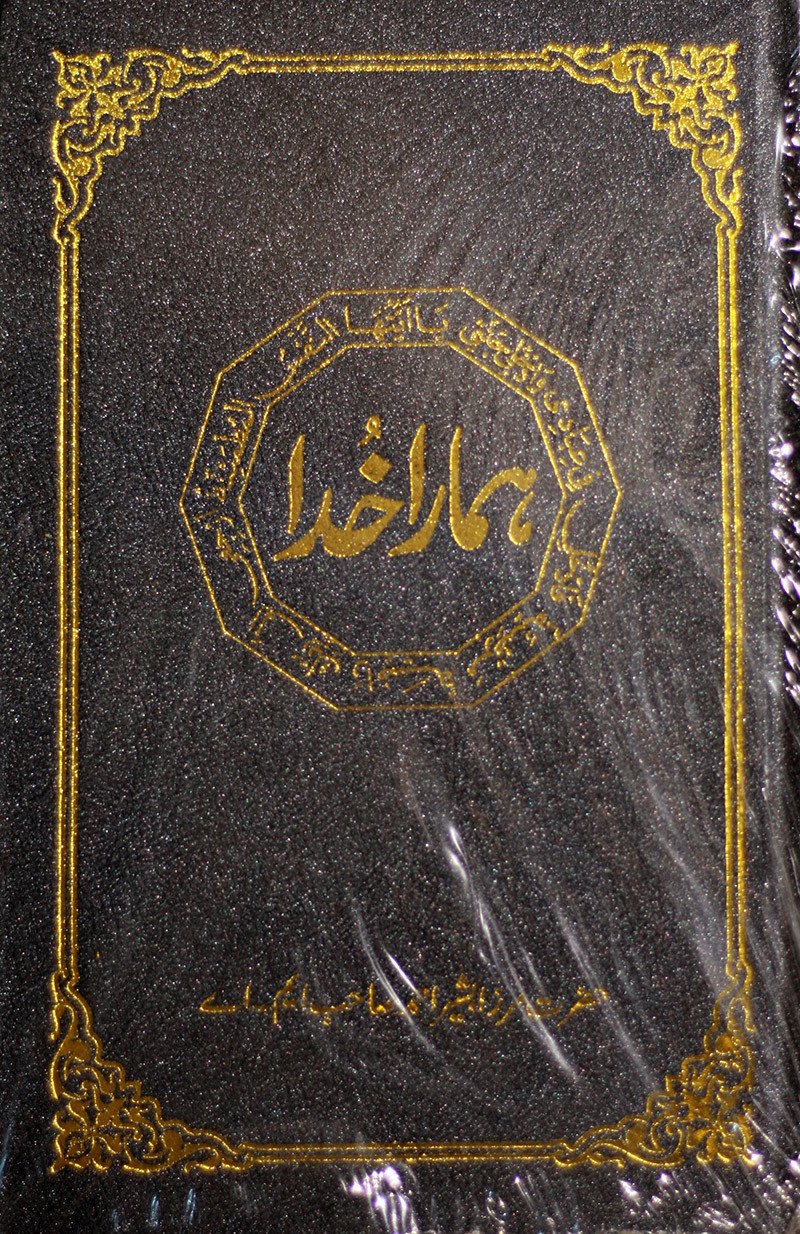Complete Text of HamaraKhuda
Content sourced fromAlislam.org
Page 1
أفى الله شَكُ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
ہمارا خدا
جس میں خدا تعالی کی ہستی کو عقلی دلائل سے ثابت کیا گیا ہے
تصنیف لطیف
حضرت مرزا بشیر احمد صاحب ایم.اے
Page 2
ہمارا خدا
Hamara Khudā
(Our God)
Urdu
By: Hadrat Mirza Bashir Ahmad, M.A.Islam International Publications Ltd;
First Published in Qadian, India in 1927
Second edition (with addition of 3 chapters)
Published in Qadian, India in 1946
Third edition Published in Rabwah in 1955
Re-printed in 2005
Present edition published in UK in 2007
Published by:
Islam International Publications Limited
"Islamabad"
Sheephatch Lane
Tilford, Surrey GU102AQ
United Kingdom
Printed in UK at:
Raqeem Press,
Tilford, Surrey
ISBN 1 85372 937 X
Page 3
بسم الله الرحمن الرحيم
نحمده ونصلى على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود
خدا تعالیٰ کی ہستی کے متعلق ابتداء ہی سے شیطان انسان کے دل میں وساوس
اور شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے.لیکن جوں جوں انسان دنیاوی ترقیات
حاصل کرتا چلا جاتا ہے اور اسے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں سے مزید نوازتا ہے تو شیطان پہلے
سے بڑھ کر اور زیادہ زور سے کمزور ایمان والوں اور آرام طلب افراد کو اس بارہ میں گمراہ
کرنے کی کوشش میں مصروف عمل ہو جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس زمانہ میں مختلف
کتب بازار میں ایسی دستیاب ہیں جن میں دہریت کا پرچار کیا جارہا ہے اور بعض کو تو
بہت مقبولیت حاصل ہے.جماعت احمدیہ کی طرف سے سیدنا حضرت مرزا مسرور احمد خلیفہ المسح الخامس
ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کی زیر ہدایت حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ عنہ کی
تصنیف ”ہمارا خدا طبع کروائی جارہی ہے اور اس کا انگریزی ترجمہ بھی Our God
کے نام سے طبع کروایا جارہا ہے تا کہ ہمارے نوجوانوں کو بالخصوص خدا تعالیٰ کی ہستی کے
دلائل سے آگاہی ہو اور اس بارہ میں جو شکوک وشبہات پیدا ہو سکتے ہیں، ان کے
جوابات کا پتہ چل سکے.خدا تعالیٰ کی ہستی کے متعلق بالعموم جو شبہات پیدا ہو سکتے ہیں،
66,
ان کے تسلی بخش جوابات اس کتاب میں موجود ہیں.اس سلسلہ میں حضرت مرزا طاہر احمد صاحب خلیفہ امسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ کی
تصنیف Revelation, Rationality, Knowledge and Truth
بھی بہت مفید کتاب ہے جسے ہمیں نہ صرف خود مطالعہ کرنا چاہئے بلکہ اپنے جاننے
3
Page 4
والوں، عزیزوں اور احباب کو بھی مطالعہ کے لئے دینا چاہئے.اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ محض اپنے فضل وکرم سے ہماری مدد فرمائے اور ہم
حتی المقدور دہریت کے خیالات کا رڈ کر کے بہتوں کو خدا تعالیٰ کی ہستی کے قائل
کرواتے ہوئے اُس کے پرستار بنانے والے ہوں.آمین.کتاب ”ہمارا خدا “ کو از سرنومحمود احمد ملک صاحب (مرکزی شعبہ کمپیوٹر یو کے )
نے ٹائپ کیا ہے.اس کے کچھ حصہ کی پروف ریڈنگ میں خاکسار کی مدد مجید احمد
سیالکوٹی صاحب نے کی جبکہ معتد بہ حصہ کی پروف ریڈنگ میں خاکسار کی مددخاکسار کی
اہلیہ ریحانہ شمس صاحبہ نے کی ہے.اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے.آمین
خاکسار
منیر الدین شمس
ایڈیشنل وکیل التصنیف - لندن
فروری 2007ء
4
Page 5
عرض حال ایڈیشن سوم
یہ کتاب یعنی ” ہمارا خدا میں نے ابتداء 1925ء کے وسط میں لکھنی شروع کی
تھی مگر بعض موانع کی وجہ سے اس کی تصنیف کا کام درمیان میں رک گیا اور بالآخر میں
نے اسے نومبر 1927ء میں ختم کیا اور دسمبر 1927ء میں اس کا پہلا ایڈیشن شائع ہوا.مجھے خوشی ہے کہ ملک کے نو تعلیمیافتہ طبقہ نے جس کے لئے یہ کتاب لکھی گئی تھی اسے
پسندیدگی کی نظر سے دیکھا اور بعض ڈگمگاتے ہوئے قدموں اور بعض لرزتے ہوئے
دلوں نے میری اس کتاب کے ذریعہ روحانی تسکین حاصل کی.فَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى
ذلِكَ وَ اللهُ الْمُوَفِّقُ الْمُسْتَعَانُ -
دو
اس کتاب کا دوسرا ایڈیشن دسمبر 1946ء میں قادیان سے شائع ہوا تھا.اس
ایڈیشن میں میں نے معمولی نظر ثانی کے علاوہ تین مختصر سے بابوں کا اضافہ کیا تھا.ایک
باب جو دہریت کی ساتویں دلیل اور اس کارڈ“ کے عنوان کے ماتحت درج کتاب کیا
گیا، یورپ کے مشہور فلاسفر اور سائینسدان سگمنڈ فرائیڈ کے ایک نظریہ پر مبنی ہے اور
دوسرا باب ” کمیونزم یعنی اشتراکیت کے متعلق ہے جو آجکل گو یاد ہریت کی علمبر دار بنی
ہوئی ہے.مگر یہ دونوں اضافے نہایت اختصار کے ساتھ کئے گئے تھے کیونکہ اس کتاب
میں اس سے زیادہ تفصیل کی گنجائش نہیں تھی.تیسرا اضافہ ایک مختصر ” تمہ“ کی صورت
میں تھا جس میں کتاب کے دوسرے حصہ کی جو ہستی باری تعالیٰ کے متعلق ” مشاہدہ
والے دلائل سے تعلق رکھتا ہے ایک اُڑتی ہوئی جھلک دکھائی گئی تھی.موجودہ ایڈیشن اس
کتاب کا تیسرا ایڈیشن ہے جسے میں صیغہ تالیف و تصنیف صدر انجمن احمد یہ ربوہ کی
5
Page 6
درخواست پر معمولی لفظی نظر ثانی کے بعد سپر طبع کر رہا ہوں.اللہ تعالیٰ اسے بیش از پیش
قبولیت سے نوازے.اسلام میں ایمان کے ارکان پانچ سمجھے جاتے ہیں.یعنی (1) خدا کا وجود (2)
نبی کا وجود.(3) کتاب اللہ (4) ملائکۃ اللہ اور (5) بعث بعد الموت، لیکن غور سے
دیکھا جائے تو دراصل پہلے دور کنوں میں ہی دین مکمل ہو جاتا ہے اور باقی ارکان گویا ان
کے تابع اور انہی کے اندر شامل ہیں.اور میرے لئے یہ بات بے حد خوشی اور فخر کا
باعث ہے کہ مجھے ذات باری تعالیٰ اور حضرت سید المرسلین ﷺ کے متعلق اپنی سمجھ اور
طاقت کے مطابق حقیر خدمت کا موقعہ میسر آیا ہے.یعنی خدا کی ہستی کے متعلق مجھے
”ہمارا خدا کی تصنیف کی توفیق ملی اور آنحضرت ﷺ کے متعلق ” سيرة خاتم النبین
کی تصنیف کی سعادت حاصل ہوئی.احباب دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بقیہ
ایام زندگی میں یعنی زاں پیشتر کہ بانگ برآید فلاں نماند ایسی خدمت کی توفیق عطا
کرے جو اس کی خاص رضا کے حصول کا موجب اور اس کے دین کی حقیقی ضرورت کو
پورا کرنے والی ہو.آمین یا ارحم الراحمین.الله
خاکسار
مرزا بشیر احمد
ربوہ یکم ستمبر 1955ء
بعض کے نزدیک ارکان ایمان چھ ہیں.جن میں وہ قضاء وقد رکو شمار کرتے ہیں.( پبلشرز )
6
Page 7
35
11
11
13
17
24
35
36
40
تعارف کتاب
عرض حال ایڈیشن سوم
فہرست مضامین ہستی باری تعالیٰ کے متعلق چند ابتدائی تصریحات
تمہید
اس زمانہ میں ایمان باللہ کی حالت
اگر خُدا ہے تو وہ نظر کیوں نہیں آتا ؟
خدا کے متعلق کیوں تحقیق کی جائے؟
خدا کے متعلق تحقیق کا طریق
تحقیق کے میدان میں نیت کا دخل
ایمان باللہ کے دو درجے
خدا کی ہستی کے متعلق عقلی دلائل
احتیاطی دلیل
فطری دلیل
کائنات خلق اور نظام عالم کی دلیل
مغربی محققین اور خدا کا عقیدہ
فلسفۂ جدید کیوں ٹھوکر کا موجب بن رہا ہے؟
خدا غیر
مخلوق ہے
47
47
50
57
71
87
96
7
Page 8
102
110
120
123
126
129
148
162
163
173
187
188
191
191
196
198
201
201
203
کیوں نہ اس دنیا کو ہی غیر مخلوق سمجھ لیا جائے؟
نیکی ، بدی کے شعور کی دلیل
قبولیت عامہ کی دلیل
کیا خدا کا عقیدہ تو ہم پرستی کا نتیجہ ہے؟
یقین کے تین درجے
غلبہ رسل کی دلیل
شہادتِ صالحین کی دلیل
ایمان باللہ کے عظیم الشان فوائد
ایمان باللہ وحدت اور اخوت کا جذبہ پیدا کرتا ہے
کیا مذہب دنیا میں جنگ و جدال کا موجب ہے؟
ایک درمیانی عرض حال
خدا کا عقیدہ بدی کے ارتکاب سے روکتا ہے
خدا کا عقیدہ نیکی کی طرف رغبت پیدا کرتا ہے
خدا کا عقیدہ حقائق الاشیاء کی تحقیق میں محمد ہے
خدا کا عقیدہ اطمینانِ قلب پیدا کرتا ہے
خدا کے عقیدہ سے اخلاق کا معیار قائم ہوتا ہے
دہریت کے دلائل کی مختصر تر دید
تین قسم کی دہریت
دہریت کی پہلی دلیل اور اس کا رڈ
8
Page 9
205
206
209
210
211
216
220
223
226
229
231
231
240
245
248
250
دہریت کی دوسری دلیل اور اس کارڈ
دہریت کی تیسری دلیل اور اس کارڈ
دہریت کی چوتھی دلیل اور اس کارڈ
دہریت کی پانچویں دلیل اور اس کا رڈ
قانون
نیچر اور قانونِ شریعت میں امتیاز کرنا ضروری ہے
تناسخ کا عقیدہ کس طرح پیدا ہوا ہے.انسانی ترقی کے لئے قانون
نیچر کا قانون شریعت سے جُدا
اور آزا در ہنا ضروری ہے.دنیا میں گناہ کا وجود کیوں پایا جاتا ہے؟
دہریت کی چھٹی دلیل اور اس کا رڈ
دنیا میں ضرررساں چیزیں کیوں پیدا کی گئی ہیں؟
دہریت کی ساتویں دلیل اور اس کا رڈ
فرائیڈ کے ایک نظریہ کا بطلان
کمیونزم اور خدا کا عقیدہ
اسلام میں دولت کی منصفانہ تقسیم کا انتظام
خاتمہ
9
Page 11
بسم الله الرحمن الرحيم
نحمده ونصلى على رسوله الكريم
خُدا کے فضل اور رحم کے ساتھ
هو الناصر
ہستی باری تعالیٰ کے متعلق چند ابتدائی تصریحات
ایک عرصہ سے میرے دل میں یہ خواہش تھی کہ اپنے نو جوان عزیزوں اور
دوستوں کے لئے ہستی باری تعالیٰ کے متعلق ایک مضمون تحریر کروں جس میں مختصر اور
عام فہم طریق پر بعض وہ دلائل بیان کئے جائیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمارا ایک
خالق و مالک خدا ہے جس کے ساتھ تعلق پیدا کرنا ہمارے لئے از بس ضروری ہے اور
پھر اس مضمون میں یہ بھی بتایا جائے کہ ہمارے خدا کے یہ یہ صفات ہیں اور اس کے
ساتھ تعلق پیدا کرنے میں یہ یہ فوائد ہیں اور نیز یہ کہ اس کے ساتھ کس طرح تعلق پیدا کیا
جاسکتا ہے وغیر ذالک.مگر آج تک کئی ایک وجوہات سے میں اپنے اس ارادہ کو
عملی جامہ نہیں پہنا سکا.اب چند دن ہوئے کہ ایک عزیز نے (خُدا اُسے حسناتِ
دارین سے متمتع فرمائے ) مجھ سے خدا تعالیٰ کے متعلق اپنے رنگ میں بعض سوالات
کئے جس سے میری وہ قدیم خواہش میرے دل میں پھر تازہ ہوگئی اور میں نے اس عزیز
کے سوالات کو ایک تحریک غیبی سمجھ کر اس مضمون کے شروع کر دینے کا ارادہ کر لیا.یہ عزیز اب فوت ہو چکا ہے.اللہ تعالیٰ اس سے مغفرت اور فضل اور رحمت کا سلوک فرمائے
اُ
11
Page 12
وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيْبُ
میرے اس بیان سے یہ نہ سمجھا جائے کہ میں نے اس مضمون کے واسطے کوئی
خاص تیاری کی ہے یا یہ کہ میں اس سوال پر علمی لحاظ سے کوئی خاص روشنی ڈالنا چاہتا
ہوں.میرا منشا صرف یہ ہے کہ اس مسئلہ کے متعلق جو میرے موجودہ معلومات ہیں اُن
میں سے بعض کو جو عام فہم ہیں میں اپنے نو جوان عزیزوں اور دوستوں کے لئے مختصر اور
سادہ طریق پر تحریر کر دوں تا اگر خدا چاہے تو میرا یہ مضمون کسی بھٹکتی ہوئی رُوح کی ہدایت
اور کسی لڑکھڑاتے ہوئے قدم کی استواری اور کسی بیقرار اور پریشان دل کی تسکین کا
موجب ہو اور ہمارے عزیز اپنے اُس مہربان اور سب محبت کرنے والوں سے بڑھ کر
محبت کرنے والے آقا و مالک کو پہنچا نہیں جس کا پہچانا اور جس تک پہنچنا ہماری زندگی کا
مقصد ہے.عمر قبل اس کے کہ میں اس مضمون کو شروع کروں میں خدا سے
دعا کرنا چاہتا ہوں
کہ اے میرے مولیٰ ! تو میری سب کمزوریوں پر اطلاع رکھتا ہے اور میری علمی اور عملی
حالت بھی تجھ سے پوشیدہ نہیں.تو مجھے اپنے فضل سے یہ طاقت اور توفیق عطا کر کہ میں
تیری رضا کے ماتحت اس مضمون کو تکمیل تک پہنچا سکوں اور تُو میرے الفاظ میں اثر پیدا کر
اور میرے قلم کو صرف حق و راستی کے طریق پر چلا تا تیرے بندے میرے اس بیان سے
فائدہ اٹھا ئیں اور تجھے پہچان کر اپنی زندگی کا اصل مقصد حاصل کریں اور اے میرے
ہادی وراہنما! گوئیں میں اپنی نیت کو نیک پاتا ہوں لیکن خود میرے متعلق بھی تجھے وہ علم
حاصل ہے جو مجھے حاصل نہیں.پس اگر تیرے علم میں میری نیت میں کوئی مخفی فساد ہے تو
مجھ ناچیز پر رحم فرما اور میری نیت کی اصلاح کر دے تا میری شامت اعمال کی وجہ سے میرا
یہ بیان اُن برکات سے محروم نہ ہو جائے جو تیری طرف سے صداقت کی تائید میں نازل
ہوا کرتی ہیں.اے میرے آقا و مالک ! تو ایسا ہی کر.آمین یا ارحم الراحمین.12
Page 13
اس زمانہ میں ایمان باللہ کی حالت
سب سے پہلے میں اس جگہ اس حد درجہ قابلِ افسوس اور نہایت درد ناک حالت
کا اظہار کرنا چاہتا ہوں جو اس زمانہ میں ایمان باللہ کے متعلق لوگوں میں عام طور پر پائی
جاتی ہے.کہنے کو تو جتنے مذاہب بھی دنیا میں موجود ہیں وہ سب خدا کے قائل ہیں اور ان
مذاہب کی طرف منسوب ہونے والے لوگ بھی باستثناء ایک نہایت قلیل تعداد کے جو
ہستی باری تعالیٰ کی برملا منکر ہے خدا پر ایمان لانے کے مدعی ہیں لیکن اگر نظر غور سے
دیکھا جائے اور لوگوں کی ایمانی حالت کا گہرا مطالعہ کیا جائے تو صاف ظاہر ہو جاتا ہے
کہ یہ ایمان ایک محض رسمی ایمان ہے جسے حقیقت سے ذرہ بھر بھی تعلق نہیں.چونکہ
لوگوں کا مذہب انہیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ تمہارا ایک خدا ہے اور وہ اپنے باپ دادوں سے
بھی یہی سنتے چلے آئے ہیں کہ ہمارا ایک خدا ہے اور وہ یہ بھی محسوس کرتے ہیں کہ قومی
شیرازے کو منتشر ہونے سے بچانے کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ ظاہری طور پر اپنے
مذہب کے بنیادی اصول پر قائم رہیں اور پھر ان کے دلوں میں گاہے گا ہے یہ فطری آواز
بھی اُٹھتی رہتی ہے کہ ممکن ہے واقعی ہمارا کوئی خدا ہو اس لئے وہ انکار کی جرات نہیں
کرتے اور ظاہراً اسی عقیدہ پر قائم ہیں کہ اُن کا ایک خُدا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ
خدا کے قائل نہیں اور اُن کے دل ایمان سے اُسی طرح خالی ہیں جس طرح ایک اُجڑا ہوا
مکان مکین سے خالی ہوتا ہے.میں یہ بات کسی خاص قوم کے افراد یا کسی خاص مذہب کے متبعین کے متعلق نہیں
کہتا بلکہ تمام مذاہب اور تمام دنیا کے متعلق کہتا ہوں کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ تمام
مذاہب کے متبعین یعنی زرتشتی.بڑھ.ہندو.یہودی.عیسائی.سکھ.مسلمان وغیرہ
سب میں یہ زہر جسے بے ایمانی کا زہر کہنا چاہیے کم و بیش سرایت کر چکا ہے اور مادیت کی
گرم اور شرر بار ہواؤں نے دنیا کا کوئی چمنستانِ ایمان نہیں چھوڑا کہ اسے جلا کر خاک نہ
13
Page 14
کر دیا ہو.میرے اس دعوئی پر اگر کوئی دلیل مانگے تو میں بفضلہ تعالیٰ ایسے دلائل پیش کر
سکتا ہوں جن سے کسی عقلمند غیر متعصب شخص کو انکار نہیں ہوسکتا، لیکن اس جگہ میں اس
بات میں شک کرنے والوں سے صرف یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا وہ اپنے دل کی
حالت کا مطالعہ کر کے اور اپنے گردو پیش کے لوگوں کے حالات
کو دیکھ کر دیانتداری کے
ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اور ان کے ملنے والے دوسرے لوگ خدا پر واقعی ایمان رکھتے
ہیں؟ ایمان سے میری مُراد رسمی سنا سنایا ورثہ کا ایمان نہیں بلکہ زندہ حقیقی ایمان مُراد
ہے.کیا خدا کی ہستی اُن کے لئے ایسی ہی محسوس و مشہور ہے جیسے دنیا کی مادی چیز میں اُن
کے لئے محسوس و مشہور ہیں؟ یعنی کیا خدا کے متعلق وہ ایسا ایمان رکھتے ہیں جیسا کہ مثلاً
انہیں یہ ایمان ہے کہ یہ سورج ہے اور یہ چاند ہے اور یہ پہاڑ ہے اور یہ دریا ہے اور یہ
ہمارا امکان ہے اور یہ ہمارا باپ ہے اور یہ ہمارا دوست ہے؟ اگر ایسا نہیں تو پھر خوب سمجھ
لو کہ یہ کوئی ایمان نہیں ہے بلکہ محض ایک شک کا مقام ہے اور تم ایک مُردہ اور متعفن لاش
کو زندوں کی طرح چھاتی سے لگائے بیٹھے ہو.اور اگر یہ کہو کہ یہ مرتبہ ایمان کا جو اس جگہ بیان کیا گیا ہے یہ تو انتہائی مرتبہ ایمان
کا ہے جس تک پہنچنے والے بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں اور صرف خاص خاص لوگوں کو
ہی یہ مقام حاصل ہوتا ہے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ بات تمہاری ناواقفی کا ایک مزید ثبوت
ہے کیونکہ ایمان کا انتہائی مرتبہ تو وہ ہے جس کی ہوا بھی ابھی تم تک نہیں پہنچی اور شاید تم
میں سے اکثر لوگ اس کا نقشہ بھی اپنے ذہن میں نہیں لا سکتے اور یہ مرتبہ ایمان کا جواو پر
بیان کیا گیا ہے یعنی خدا کے متعلق ایسا ایمان ہونا جیسا کہ اس دُنیا کی مادی چیزوں کے
متعلق انسان کو حاصل ہوتا ہے یہ ایمان کے درمیانی مراتب میں سے ایک مرتبہ ہے.کیا تم نے حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول نہیں پڑھا جس کا مطلب یہ
ہے کہ ایمان کے عام مراتب میں سے ایک مرتبہ یہ ہے کہ انسان آگ میں ڈالا جا کر
14
Page 15
خاک ہو جانا پسند کریگا مگر ایمان کو ہاتھ سے نہیں چھوڑیگا، لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر تم
ایمان کے اس مرتبہ سے اپنے آپ کو فروتر پاتے ہو تو کم از کم میرا تم سے یہ سوال ہے کہ
کیا تم دیانتداری کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہو کہ تمہارا ایمان ایک زندہ حقیقت کے طور پر
تمہاری زندگی پر عملاً اثر انداز ہورہا ہے.یعنی کیا تم اپنے دل میں واقعی اللہ تعالیٰ کی محبت
اور اس کی ناراضگی کا خوف محسوس کرتے ہو اور کیا تمہارا ایمان تمہیں واقعی نیکی کی تحریک
کرتا اور بدی سے روکتا ہے؟ اور کیا واقعی تمام اُمور میں تمہارا اصل بھروسہ خدا پر ہوتا ہے
اور مادی اسباب پر
نہیں ہوتا ؟
میرا یہ مطلب
نہیں کہ کیا تم بھی اپنے دل میں خدا کے ساتھ وابستگی محسوس کرتے
ہو یا نہیں یا کبھی اللہ تعالیٰ کا خیال تمہیں گناہ سے روکتا اور نیکی کی تحریک کرتا ہے یا نہیں یا
کبھی مادی اسباب سے آگے گذر کر تمہاری نظر خدا تک پہنچتی ہے یا نہیں؟ کیونکہ کبھی کبھی
ایسا ہو جانا ایمان کی حالت کا نتیجہ نہیں کہلا سکتا.بلکہ ایسی حالت اُس شخص کی بھی ہوسکتی
ہے جسے صرف اس قدر بصیرت حاصل ہے کہ وہ خدا کا انکار نہیں کرتا اور گاہے گا ہے اُس
کی طبیعت میں یہ خیال بھی پیدا ہو جاتا ہے کہ شاید واقعی کوئی خدا ہو جس نے مجھے پیدا کیا
ہے اور جو اس تمام کارخانہ عالم کا چلانے والا ہے اور جس کے سامنے کسی دن میں نے
کھڑا ہونا ہے.ایسا شخص یقیناً کبھی کبھی خدا کے اس خیالی بت کے ساتھ ایک حد تک
وابستگی محسوس کر یگا اور اس کا یہ خیال کبھی کبھی اُسے گناہ سے بھی روکے گا اور کبھی کبھی نیکی
کی بھی تحریک کریگا اور گاہے گا ہے اُس کی نظر مادی اسباب سے گذر کر خدا تک بھی پہنچے
گی اور وہ محسوس کریگا کہ اصل بھروسہ کے قابل صرف خدا کی ذات ہے لیکن ظاہر ہے کہ
یہ حالت ایمان کی حالت نہیں کہلا سکتی بلکہ دراصل ایک شک کی حالت ہے جو اس کی
طبیعت میں کبھی ایک طرف کا اور کبھی دوسری طرف کا اثر پیدا کرتی رہتی ہے ایمان کی
حالت تبھی سمجھی جائیگی جب خدا کے متعلق ایک زندہ یقین کی صورت پیدا ہو جائے اور یہ
15
Page 16
یقین ایک مستقل جذ بہ کے طور پر علی وجہ البصیرت دل میں قائم ہو جو انسان کی زندگی کا
ایک حصہ بن جائے اور اُس کی روح کی غذا ہو جائے اور اس کے لئے ہر وقت ایک ایسی
شمع ہدایت کا کام دے جو اسے گناہ کے تاریک رستوں پر متنبہ کرتی رہے اور اُس کے
ذریعہ سے نیکی کے راستے اُس کی آنکھوں کے سامنے روشن ہوتے رہیں اور تمام مادی
اسباب اُس کی نظر میں بیچ ہو جائیں یعنی اُن اسباب پر اس کا بھروسہ نہ رہے بلکہ اس کا
اصل بھر وسہ صرف خدا تعالیٰ کی ذات پر ہو جو تمام اسباب کا پیدا کرنے والا ہے اور خدا
کی محبت کی آگ اس کے دل میں سوزاں رہے اور اُس کی ناراضگی کا خوف اس کے دل
پر غالب ہو.اب دیانتداری کے ساتھ بتاؤ کہ کیا تم واقعی ایسا ایمان اپنے دلوں میں پاتے
ہو؟ اگر نہیں اور یقینا نہیں تو اپنے آپ کو مومن کہتے ہوئے شرماؤ اور اُس ایمان کی تلاش
میں لگ جاؤ جو آسمان سے اترتا ہے اور بجلی کے ایک زبر دست لیمپ کی طرح دل کے
دور دراز اور تاریک و تار کونوں کو منور کر دیتا ہے جس کے بعد خدا کا وجود ایک خیالی بُت
نہیں رہتا جسے تمہارے دماغوں نے گھڑا ہو بلکہ وہ ایک زندہ تی و قیوم قدیر وعزیز نگر
مشفق و مہربان بادشاہ نظر آتا ہے جس کی حکومت دیکھنے والوں کے لئے اُن حکومتوں
سے بھی بہت بڑھ چڑھ کر محسوس و مشہور ہوتی ہے جو تم اس دنیا میں دنیاوی بادشاہوں کی
دیکھتے ہو.الغرض یہ ایک بین حقیقت ہے جس سے انکار نہیں ہوسکتا کہ اس زمانہ میں حقیقی
ایمان دنیا سے مفقود ہے اور نہ صرف یہ کہ عوام کے دلوں سے مفقود ہے بلکہ وہ لوگ جو
مذہبی لیڈر کہلاتے ہیں اور لوگوں کو ایمان پر قائم کرنے کا دم بھرتے ہیں اُن کے دل بھی
دراصل دہریت کا شکار ہو چکے ہیں.وہ یا تو دنیا کو دھوکہ دیتے ہیں یا خود اپنے متعلق
دھو کہ خوردہ ہیں کیونکہ زبان پر تو سب کچھ ہے مگر دل میں کچھ بھی نہیں.یقینا اس وقت
16
Page 17
دنیا روحانیت اور کچے ایمان کے لحاظ سے ایک خطرناک تاریکی میں گھری ہوئی ہے اور
کوئی کمزور مدھم اور ٹمٹماتا ہوا چراغ بھی کسی کونے میں نظر نہیں آتا جس سے گرتے
پڑتے اور ٹھوکریں کھاتے ہوئے مسافروں کا رستہ تھوڑا بہت روشن ہو سکے.کیا ایسے
تاریک و تار وقت میں ضرورت نہ تھی کہ قدیم سنت کے مطابق ہمارے مہربان خدا کی
تجلیات کا سورج اس کے کسی پاک بندے کے افق قلب سے طلوع ہو کر دنیا میں اُجالا
کرے؟ میرے عزیز واُٹھو اور اپنی جبینِ نیاز کو آستانہ الوہیت پر رکھ دو کیونکہ تمہارے
خُدا نے تمہاری حالت کو دیکھا اور تمہارے لئے اپنے ایک رُوحانی سورج کو اُفق مشرق
سے بلند کر دیا.اب اپنے دل کی کھڑکیاں کھولو اور اس سورج کی نورانی کرنوں کو اُس
کے اندر جانے دو تا شکوک و شبہات کی تاریکی دُور ہو اور رات کی ظلمت دن کی روشنی
میں بدل جائے.اگر خُدا ہے تو وہ نظر کیوں نہیں آتا ؟
اس کے بعد قبل اس کے کہ میں اصل مضمون شروع کروں ایک شبہ کا ازالہ کرنا
چاہتا ہوں جو خدا تعالیٰ کے متعلق عموماً لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوا کرتا ہے اور وہ یہ کہ
اگر کوئی خدا ہے تو وہ ہمیں نظر کیوں نہیں آتا؟ یہ شبہ آج کا نہیں بلکہ ہمیشہ سے چلا آیا
ہے.چنانچہ قرآن شریف سے پتہ چلتا ہے کہ عرب کے دہریوں نے آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم سے بھی یہی سوال کیا تھا کہ ہمیں خدا دکھا دو پھر ہم مان لیں گے مگر میں جب
کبھی اس شبہ کا ذکر سنتا یا پڑھتا ہوں تو مجھے اس شبہ کے پیدا کرنے والوں کی حالت پر
رحم آتا ہے.افسوس ! جب انسان ٹھو کر کھانے لگتا ہے تو اس کی عقل پر ایسا غفلت کا پردہ
آجاتا ہے کہ وہ کھلی کھلی بینات سے بھی انکار کرنے لگ جاتا ہے.گذشتہ زمانوں میں
سورة بنی اسرائیل - رکوع 10 آیت : 93
17
Page 18
اگر یہ اعتراض ہوتا تھا تو گو بہر حال لغو اور بیہودہ ہی تھا مگر پھر بھی بعض نادانوں کو عارضی
طور پر دھوکے میں ڈال سکتا تھا لیکن اس زمانہ میں اس اعتراض کا پیدا ہونا واقعی حیرت
انگیز ہے اور مجھے اس شخص کی دماغی حالت پر سخت تعجب آیا کرتا ہے جو اس قسم کے شبہات
سے اپنے انکار میں تسلی پانے کی کوشش کرتا ہے.میرے نزدیک اس قسم کے اعتراضات
کا اٹھا نا صرف چھوٹی عمر کے بچوں کے لئے جائز ہوسکتا ہے اور یا پھر یہ مجا نین کا کام ہے
مگر بہر حال چونکہ یہ ایک عام شبہ ہے اس لئے اس کا ازالہ ضروری ہے.چنانچہ میں مختصر
طور پر اس شبہ کا جواب دیکر اصل مضمون کی طرف متوجہ ہوتا ہوں.جاننا چاہیے کہ دنیا میں مختلف چیزوں کے متعلق علم حاصل کرنے کے ذرائع
مختلف ہیں مثلا کسی چیز کے متعلق ہمیں دیکھنے سے علم حاصل ہوتا ہے کسی کے متعلق سننے
سے کسی کے متعلق چکھنے سے کسی کے متعلق سُونگھنے سے کسی کے متعلق ٹولنے سے اور کسی
کے متعلق چھونے سے وغیرہ وغیرہ اور یہ سب علم ایک جیسے ہی یقینی اور قابلِ اعتماد ہوتے
ہیں اور ہمیں ہر گز یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ہم یہ مطالبہ کریں کہ جب تک ہمیں فلاں چیز
کے متعلق فلاں ذریعہ سے علم حاصل نہیں ہوگا ہم اُسے نہیں مانیں گے مثلاً رنگوں کے
متعلق علم حاصل کرنے کا ذریعہ آنکھ ہے یعنی آنکھ کے ذریعہ ہم یہ پتہ لگا سکتے ہیں کہ
فلاں رنگ اس قسم کا ہے اور فلاں اس قسم کا.اسی طرح بُو کے متعلق علم حاصل کرنے کا
ذریعہ ناک ہے اور آواز کے لئے کان ہیں.اب یہ سراسر دیوانگی ہوگی اگر ہم یہ کہیں کہ
جب تک ہم آنکھ کے ذریعہ فلاں خوشبو کو نہیں دیکھ لیں گے ہم نہیں مانیں گے.یا جب
تک ہم ناک کے ذریعہ فلاں رنگ کو سونگھ نہ سکیں گے.ہم تسلیم نہیں کرینگے.یا جب تک
ہم فلاں آواز کو ہاتھ سے ٹول نہ لیں گے ہماری تسلی نہ ہوگی.جو شخص ایسے اعتراضات
اُٹھائیگا وہ پاگل کہلائے گا اور اگر وہ پاگل خانہ میں نہیں بھیجا جائیگا تو کم از کم گلی کے شریر
اور شوخ بچوں
کا تماشہ ضرور بن جائیگا.مگر تعجب ہے کہ خدا تعالیٰ کے متعلق لوگ آئے دن
18
Page 19
ایسے اعتراضات اٹھاتے رہتے ہیں اور پھر بھی وہ عقلمند سمجھے جاتے ہیں اور کوئی خدا
کا بندہ ان عقل کے اندھوں سے نہیں پوچھتا کہ آخر اس جنون کی وجہ کیا ہے؟ کیا خدا کی
ذات ہی ایسی رہ گئی ہے کہ تم اسے ایسی تمسخر آمیز دیوانگی کا نشانہ بناؤ؟ افسوس !صد
افسوس !!
یہاں تک میں نے صرف حواس ظاہری کا ذکر کیا ہے جن سے دُنیا کی بہت سی
چیزوں کے متعلق علم حاصل ہوتا ہے، لیکن اس دُنیا میں بیشمار چیزیں ایسی بھی ہیں جن کا
علم حواس ظاہری میں سے کسی جس کے ذریعہ بھی براہ راست حاصل نہیں ہوسکتا اور
باوجود اس کے ہمیں ان کے متعلق ایسا ہی یقین حاصل ہے جیسا کہ ان چیزوں کے متعلق
حاصل ہے جن کا علم حواس ظاہری کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے.مثال کے طور پر قوت
مقناطیسی کو لے لو.کیا تم اُسے آنکھ سے دیکھ سکتے ہو یا کان سے سُن سکتے ہو یا ناک سے
سونگھ سکتے ہو یا زبان سے چکھ سکتے ہو یا ہاتھ سے چھو سکتے ہو؟ ہر گز نہیں.مگر کیا تم میں
سے کسی کو جرات ہے کہ اس طاقت کا انکار کرے؟ میں پھر کہوں گا کہ ہرگز نہیں.کیونکہ
گو تم اس طاقت کو اپنی کسی ظاہری حسن سے براہِ راست محسوس نہیں کر سکتے لیکن اُس کے
اثرات
و افعال تم یقینی طور پر محسوس کرتے ہو اور اثرات
کا علم تمہارے اندر ایسا ہی یقینی
علم پیدا کر دیتا ہے جیسا کہ خود کسی چیز کا براہ راست محسوس کرنا کر سکتا ہے.تم دیکھتے ہو کہ
جب ایک مقناطیسی لوہے کے قریب تم ایک عام لوہے کا ٹکڑا لاتے ہو تو وہ مقنا طیس
جھٹ اس لوہے کے ٹکڑے کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے اور جب بھی تم ایسا کرتے ہو یہی
نتیجہ نکلتا ہے جس سے تمہیں یہ علم حاصل ہوتا ہے کہ اس مقناطیسی لوہے کے اندر عام
لوہے کے علاوہ کوئی اور طاقت موجود ہے جسے تم اپنے ظاہری حواس سے براہ راست
محسوس نہیں کر سکتے مگر اس کے اثرات و افعال سے اس کا پتہ لگاتے ہو اور تمہیں کبھی یہ
حبہ نہیں گذرتا کہ چونکہ ہم نے قوت مقناطیس کو دیکھا یا سنایا سونگھا یا چکھایا چھوا نہیں اس
19
Page 20
لئے ہم اسے نہیں مان سکتے.اسی طرح بجلی کی طاقت ہے جو خود نظر نہیں آتی مگر اپنے
اثرات وافعال سے تمہارے دلوں پر حکومت کر رہی ہے.تم اپنے کمرے کا بٹن دباتے
ہو اور تمہارا پنکھا فرفر چلنے لگ جاتا ہے اور تم محسوس کرتے ہو کہ اب اس سیکھے میں کوئی
بیرونی طاقت کام کر رہی ہے جو ایک سیکنڈ قبل اس میں موجود نہ تھی حالانکہ تم نے نہ اس
طاقت کو براہ راست دیکھا نہ سنا نہ سونگھا نہ چکھا اور نہ کسی اور ظاہری حسن سے
براہ راست اسے معلوم کیا مگر تمہارا دل اس یقین سے پر ہے کہ بجلی ایک زبردست
طاقت ہے کیونکہ گو تمہارے حواس نے براہ راست بجلی کو محسوس نہیں کیا مگر اس کے
افعال و اثرات
و نتائج کو یقینی طور پر محسوس کیا ہے اس لئے تم اس کے انکار کی جرات نہیں
کر سکتے اور اس پر اسی طرح یقین لاتے ہو جیسے مثلا سورج.چاند.پہاڑ دریا وغیرہ کے
متعلق تمہیں یقین ہے.پھر مثلاً محبت کے جذبہ کولو.کوئی ہے جس نے محبت کو دیکھا ہو یا سنا ہو یا چکھا ہویا
سونگھا ہو یا ٹولا ہو یا چھوا ہو؟ اگر نہیں اور ہرگز نہیں تو میں کہتا ہوں کہ پھر تم میں سے کوئی
ہے جو محبت کے جذبہ کا انکار کر سکے؟ میں نہیں کہہ سکتا کہ میرے اس مضمون کے پڑھنے
والوں میں سے کوئی شخص خاص طور پر عشق کا دلدادہ اور محبت کا درد آشنا بھی ہے یا نہیں
لیکن اگر کوئی ہے تو میں اس سے پوچھتا ہوں کہ کیا اس نے یہ نظارہ نہیں دیکھا کہ اس
کے چھوٹے سے دل میں جو وزن میں شاید آدھ پاؤ سے بھی زیادہ نہیں ہوگا محبت کا ایک
نا پیدا کنار اور اتھاہ سمندر موجزن ہے جو جب تلاطم پر آتا ہے تو خدا کی مخلوقات میں غالباً
سب سے زیادہ مہیب اور سب سے طاقتور ہستی کہلانے کا حقدار ہو جاتا ہے اور جو ایک
کمزور اور نحیف انسان کے اندر وہ قوت و طاقت بھر دیتا ہے کہ وہ اپنے محبوب کی خاطر
پہاڑ سے ٹکراتا ہے اور صحراؤں کی خاک چھانتا ہے اور جنگل کے درندوں کے منہ میں
حس جاتا ہے اور آگ میں زندہ کو د جاتا ہے اور سمندر کی مہیب موجوں کے سامنے.20
Page 21
سینہ سپر ہوتا ہے مگر پیچھے نہیں ہٹتا.وہ راتوں کو جاگتا ہے اور دن کو دیوانہ وار پھرتا ہے اور
اپنے زندگی کے خون کو آنکھ کے رستے بہا دیتا ہے مگر دم نہیں مارتا.کیا کوئی ہے جو یہ کہے
کہ دنیا میں یہ طاقت موجود نہیں ؟ مگر اس عظیم الشان طاقت کو کس نے دیکھا ہے؟ کس
نے سنا ہے؟ کس نے سونگھا ہے؟ کس نے چکھا ہے؟ کس نے چھوا ہے؟ اسی طرح
وقت.زمانہ قوت عقل.شہوت غضب.رحم وغیرہ ایسی چیزیں ہیں جن کو تم مانتے
ہو مگر جن کو تمہارے حواس ظاہری نے کبھی براہ راست محسوس نہیں کیا.بات یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے اوپر بیان کیا ہے دنیا میں مختلف چیزوں کے متعلق
علم حاصل کرنے کے لئے مختلف ذرائع مقرر ہیں.کسی چیز کا علم دیکھنے سے حاصل ہوتا
ہے کسی کا سننے سے، کسی کا سونگھنے سے، کسی کا چکھنے سے، کسی کا چھونے سے اور کسی کا
دوسری کسی جس کے ذریعہ سے، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کا علم ظاہری حواس کے
ذریعہ سے براہِ راست حاصل ہوتا ہی نہیں بلکہ ان کا علم اُن کے اثرات و نتائج کے
مشاہدہ سے حاصل ہوتا ہے اور یہ سارے علم خواہ وہ کسی ذریعہ سے حاصل ہوں ایک سے
ہی یقینی اور قابلِ اعتماد ہوتے ہیں.اور یہ ایک طفلانہ خیال ہے کہ جب تک ہم فلاں چیز
کا علم فلاں ذریعہ سے حاصل نہ کر سکیں گے ہم اس کے وجود کے قائل نہیں ہونگے.اصل مقصود تو حصول علم ہے خواہ وہ کسی ذریعہ سے حاصل ہو.اگر وہ حاصل ہو جاتا ہے تو
ہار مطلب حل ہو گیا.کیا کوئی شخص کہ سکتا ہے کہ میں تو تب مانوں گا کہ میں نے فلاں
کمرہ کا اندرونی حصہ دیکھا لیا ہے جبکہ تم اس کمرے کی چھت پھاڑ کر مجھے اس میں چھت
کے راستہ اندر داخل کرو گے اور اگر تم دروازے کے راستہ داخل کرو گے تو پھر میں نہیں
مانوں گا.ایسے شخص سے میں یہ پوچھونگا کہ بندہ خدا تمہارا مقصود چھت کو پھاڑنا ہے یا
کمرے کے اندر جانا؟ اگر تم کمرے کے اندر داخل ہو جاتے ہو تو یہ سوال لا یعینی ہے کہ
چھت پھاڑ کر اوپر سے کمرہ کے اندر کو دتے ہو یا کہ دروازہ کے راستے داخل ہوتے ہو.21
Page 22
آخر جو رستہ کسی کمرہ کے اندر داخل ہونے کے لئے مقرر ہے اُسی سے تم اندر جا سکتے ہو
اور تمہارا یہ مطالبہ سراسر مجنونانہ ہے کہ تمہارے واسطے اس کے اندر جانے کے لئے کوئی
ایسا راستہ کھولا جائے جو تمہاری مرضی کے مطابق ہو.اگر تمہاری مرضی مانی جائے تو زید
کی کیوں نہ مانی جائے.اور اگر زید کی مانی جائے تو بکر کی کیوں نہ مانی جائے؟ گویا
مطلب یہ ہوا کہ خدا بھی تمہارے تخیلات کا کھلونا بن جائے اور نعوذ باللہ ایک بہروپیا کی
طرح جس طرح کوئی چاہے اسی طرح اپنی صفات بدلتا رہے تا تمہاری ان نازک
خیالیوں کو ٹھیس نہ لگنے پائے.افسوس ! افسوس !!مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ.لوگوں نے
خدا کی قدرکو بالکل نہیں پہچانا.عزیز و! اس بات کو خوب سمجھ لو کہ کوئی چیز جتنی کثیف ہوتی ہے اتنا ہی اس کا
ادراک یعنی اُس کے متعلق علم حاصل کرنا انسان کے ظاہری حواس کے قریب ہوتا ہے
اور جتنی کوئی چیز لطیف ہوتی ہے اتنا ہی اس کا ادراک انسان کے ظاہری حواس سے دور
ہوتا ہے اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ جو چیزیں بہت لطیف ہوتی ہیں ان کے ادراک کے
لئے عموماً ان کے اثرات و افعال و نتائج کی طرف متوجہ ہونا پڑتا ہے کیونکہ ان کا ادراک
ہمارے ظاہری حواس کے لئے براہ راست ممکن نہیں ہوتا.ان حالات میں یہ کیسے ممکن
ہے کہ خدا جو ایک الطف ترین ہستی ہے بلکہ جو خود دوسری لطیف چیزوں کو پیدا کرنے والا
ہے وہ ان مادی آنکھوں سے نظر آ جائے.پس معترض کا یہ کہنا کہ جب تک ہم خدا کو اپنی
ظاہری آنکھوں سے نہ دیکھ لیں گے ہم نہیں مانیں گے ایک فضول اور لایعنی بات ہے.اس کے یہ معنے ہیں کہ یا تو معترض کے نزدیک نعوذ باللہ خدا ایک کثیف ہستی ہے اور یا
کم از کم اس کا یہ منشا ہے کہ اُس کی خاطر خدا کو کثافت اختیار کر لینی چاہئے تا وہ اُسے
اپنی ان آنکھوں سے دیکھ کر تسلی کر سکے.مگر مشکل یہ ہے کہ دنیا میں لاکھوں لوگ اندھے
ل سورة الحج - آیت 75
22
Page 23
بھی ہیں تو کیا پھر ان لوگوں کا حق نہیں ہوگا کہ وہ یہ درخواست کریں کہ خدا تعالیٰ ہماری
خاطر کوئی ایسی کثافت اختیار کرے جس کے نتیجہ میں ہم اسے سونگھ سکیں یا چکھ سکیں یا ٹول
سکیں؟ کیا خدا تعالیٰ کے متعلق یہ تمسخرانہ طریق اختیار کرنا انسان کے لئے جو دل و دماغ
رکھنے کا مدعی ہے قابل شرم نہیں ہے؟ تم کہتے ہو کہ ہم خدا کو اس وقت تک نہیں مانیں
گے جب تک ہم اس کو ان ظاہری آنکھوں سے نہ دیکھ لینگے مگر میں کہتا ہوں کہ اگر خدا ان
آنکھوں سے نظر آنے لگے تو میرے نزدیک وہ اس قابل ہی نہیں رہے گا کہ ہم اس پر
ایمان لائیں چہ جائیکہ اس کا ماننا ہمارے لئے آسان ہو جائے.کیونکہ اس صورت میں
اس کی کئی دوسری صفات کو باطل قرار دینا ہوگا.مثلاً وہ لطیف ہے مگر اس صورت میں وہ
لطیف نہیں رہے گا بلکہ کثیف ہو جائیگا.وہ غیر محدود ہے مگر اس صورت میں وہ غیر محدود
نہیں رہے گا بلکہ محدود ہو جائیگا وغیر ذالک.اور پھر اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ اگر خدا
تمہاری خاطر یعنی اس لئے کہ تم اس پر ایمان لے آؤ کثافت اور محدودیت اختیار کرے
تو پھر تم اس وجہ سے اس کا انکار نہ کرنے لگ جاؤ گے کہ ہم کثیف اور محدود خدا کو نہیں مان
سکتے.اللہ اللہ! کیا ہی مقدس، کیا ہی دلر با اور کیا ہی کامل ہستی ہے جس کی ہر صفت پر اس
کی دوسری صفات پہرہ دار کے طور پر کھڑی ہیں.کیا مجال ہے کہ کوئی شخص اس کی کسی
صفت پر حملہ آور ہو اور پھر اس کی دوسری صفات بیدار اور فرض شناس سنتریوں کی طرح
اس شخص کو خائب و خاسر کر کے ذلت کے گڑھے میں نہ دھکیل دیں.ابھی ہم نے دیکھا
کہ معترض نے صرف خدا کے مخفی ہونے کی صفت کے متعلق شبہ پیدا کیا تھا.مگر کس طرح
اس کے لطیف ہونے کی صفت اور اس کے غیر محدود ہونے کی صفت نے فوراً سامنے
آکر اس کے اس اعتراض کو پاش پاش کر دیا.سچ ہے خدا کا حسن اسی میں ہے کہ وہ مخفی
ہو اور پھر آنکھوں کے سامنے رہے.وہ باطن ہو اور پھر ظاہر میں نظر آئے ، وہ لطیف ہو
اور پھر مادی چیزوں سے بڑھ کر محسوس و مشہودر ہے.بدقسمت ہے وہ جس نے اس نکتہ کو
23
Page 24
نہیں سمجھا کیونکہ وہ ہلاکت کہ منہ میں ہے.خلاصہ کلام یہ کہ اللہ تعالیٰ کے کمال کا یہی تقاضا ہے کہ وہ لطیف ہو اور ظاہری
آنکھوں سے مخفی رہے مگر اس وجہ سے اس کی ہستی کے متعلق ہرگز ہرگز کوئی شبہ پیدا نہیں
ہوسکتا کیونکہ اسے شناخت کرنے کے لئے اس راستہ سے بہت زیادہ یقینی او قطعی راستے
کھلے ہیں جو ہماری ان مادی آنکھوں کو میسر ہے.پس اے عزیز و اتم اس قسم کے بیہودہ
شبہات سے اپنے آپ کو ایمان جیسی قیمتی چیز سے محروم نہ کرو.کیا تم ان لوگوں کے
نقش قدم پر چلو گے جنہوں نے باوجود نہ دیکھنے کے مقناطیس اور بجلی کی طاقتوں کو مانا.وقت اور زمانہ کی حکومت کو اپنے اوپر تسلیم کیا.شہوت اور غضب کے سامنے گردنیں
جھکا ئیں.مگر اپنے خالق و مالک کو محبت و عبودیت کا خراج دینے پر رضامند نہ ہوئے؟
نہیں نہیں ! تم ایسا نہیں کرو گے.خدا کے متعلق کیوں تحقیق کی جائے؟
اب میں اصل مضمون کو شروع کرتا ہوں.سب سے پہلا سوال جو ہمارے
سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم خدا کے متعلق کیوں تحقیق کریں.یعنی ہمیں کیا ضرورت
ہے کہ اس تحقیق میں پڑیں کہ کوئی خدا ہے یا نہیں؟ واقعی جو شخص اللہ تعالیٰ کی ہستی کا قائل
نہیں ہے اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہونا ایک حد تک طبعی امر ہے کہ وہ کیوں اس تحقیق
میں بلا وجہ اپنا وقت اور اپنی توجہ صرف کرے کہ کوئی خدا ہے یا نہیں اس لئے سب سے
پہلے اس سوال کا جواب ضروری ہے.سو جاننا چاہئے کہ دنیا کی کسی چیز کی ضرورت یا عدم ضرورت کا دو طرح سے ہی
فیصلہ ہوا کرتا ہے.اوّل یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو چیز یا جو کام ہمارے سامنے ہے اس کے
اختیار کرنے میں ہمیں کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے یا نہیں.اگر فائدہ پہنچنے کی معقول امید ہو تو
24
Page 25
اسے اختیار کیا جاتا ہے ورنہ ترک کر دیا جاتا ہے.دوسرے یہ دیکھا جاتا ہے کہ کسی چیز یا
کام کے ترک کرنے میں کسی قسم کے نقصان کا احتمال تو نہیں ہے.اگر نقصان کا احتمال
نہیں ہے تو اسے اختیار کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی جاتی اور اگر احتمال ہے تو اسے اختیار
کیا جاتا ہے.پس اگر یہ ثابت ہو جائے کہ کسی چیز کے اختیار کرنے میں ہمارے واسطے
فائدہ کی امید ہے یا یہ کہ اس کے ترک کرنے میں نقصان کا اندیشہ ہے تو اس صورت میں
ہر عظمند کا یہی فتوی ہوگا کہ اسے اختیار کرنا ہمارے لئے نہ صرف مناسب بلکہ ضروری
ہے.اسی اصول کے ماتحت ہم اس ضرورت کے درجہ اہمیت کا بھی فیصلہ کر سکتے ہیں.یعنی اگر کسی چیز کا اختیار کرنا ہمارے لئے بہت بڑے فائدہ کی امید پیدا کرتا ہے تو اس کا
اختیار کرنا اسی نسبت سے ہمارے لئے بہت ضروری ہوگا.اسی طرح اگر اس کے ترک
کرنے میں بہت بڑے نقصان کا احتمال ہے تو اسی نسبت سے اس کا ترک کرنا ضروری
سمجھا جائے گا.اب آؤ اس اصول کے ماتحت ہم سوال زیر بحث پر نظر ڈالیں.سوال یہ ہے کہ
ہمیں خدا تعالیٰ کے متعلق کسی تحقیق میں پڑنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ بالفاظ دیگر اگر یہ
ثابت ہو جائے کہ ہمارا ایک خدا ہے تو کیا اسے مان لینے میں ہمیں کوئی فائدہ پہنچ سکتا
ہے یا نہیں.یا اس کے انکار کر دینے میں ہمارے لئے کسی قسم کے نقصان
کا احتمال ہے یا
نہیں؟ اس فیصلہ کے لئے ہمیں اس سوال کی نوعیت پر غور کرنا ہوگا جو خدا تعالیٰ کے
متعلق ہمارے سامنے آتا ہے.اگر تو خدا کا وجود ہمارے سامنے ایسی صورت میں پیش
کیا جاتا ہے کہ اس کا ماننانہ مانا ہمارے لئے قریباً برابر ہے اور ہماری زندگی پر اس کا کوئی
براہ راست اثر نہیں پڑتا بلکہ یہ ایک محض علمی سوال ہے تو ظاہر ہے کہ ان لوگوں کے سوا جو
علمی مذاق رکھتے ہیں اور محض علم کی خاطر کسی مسئلہ پر غور کرنے کے عادی ہیں باقی تمام
لوگ یہ حق رکھتے ہیں کہ اس تحقیق میں پڑنے سے انکار کر دیں اور اپنی توجہ کو صرف ان
25
Page 26
باتوں تک محدود رکھیں جو ان کی زندگی کے نفع نقصان پر براہ راست اثر ڈالتی ہیں.مثلاً
اگر کوئی شخص ہمارے سامنے یہ سوال پیش کرے کہ میں نے ایک نیا ستارہ دریافت کیا
ہے جو زمین سے اتنے کروڑ میل دور ہے اور جس کا ہمارے نظام شمسی سے کوئی خاص
تعلق نہیں ہے اور نہ ہماری زمین پر اس کا کوئی خاص اثر پڑ رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ سوائے
ان لوگوں کے جو علم ہیئت میں مذاق رکھتے ہیں کوئی شخص اس ستارے کے حالات
دریافت کرنے کی طرف متوجہ نہیں ہوگا.لیکن اگر فرض کرو کہ کوئی شخص یہ دعوی کرتا ہے
کہ میں نے ایک ایسی چیز دریافت کی ہے جس سے انسان کے بدن میں ایسی طاقت
پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کی طبعی عمر بہت لمبی ہو جاتی ہے اور بڑھاپے کے آثار بہت دیر کے
بعد اس میں ظاہر ہوتے ہیں اور اوسط عمر جو اس چیز کے استعمال کے بعد انسان پاسکتا
ہے ایک سو برس یا ڈیڑھ دوسو برس ہے.اور اس دعوی کا شائع کرنے والا شخص بھی کوئی
ٹھگ اور دھوکہ باز نہ ہو تو تمام دنیا بڑے شوق کے ساتھ اس طرف متوجہ ہو جائیگی.کیونکہ یہ تحقیق ایسی ہے کہ اگر یہ درست ثابت ہو تو ہر انسان کی زندگی پر اس کا بھاری اثر
پڑتا ہے.اب ہم خدا کے متعلق دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ سوال تین مختلف
جہات سے ہمارے سامنے آتا ہے.سب سے اول ہماری فطرت اس سوال کو ہمارے
سامنے پیش کرتی ہے.دوسرے عقل پیش کرتی ہے.تیسرے مذہب پیش کرتا ہے.اور
یہ تینوں ایسی صورت میں اس سوال کو ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں کہ ہمیں تحقیق کے
بغیر کوئی چارہ نہیں رہتا.سب سے پہلے میں فطرت
کو لیتا ہوں.ہر شخص جو غور کرنے کا مادہ رکھتا ہے اور
بعد کی خراب تربیت نے اس کی فطرت پر ظلمت اور جہالت کے پردے نہیں ڈال دیئے
یہ محسوس کریگا کہ اس کی فطرت گاہے گاہے اس کے اندر یہ سوال پیدا کرتی رہتی ہے کہ
ممکن ہے میرا کوئی خدا ہو جس نے مجھے پیدا کیا ہو اور جو اس تمام کارخانہ عالم کا چلانے
26
Page 27
والا ہو.اور اس سوال کے ساتھ ساتھ ہی یہ سوال بھی طبعاً ہمارے اندر پیدا ہورہا ہے کہ
اگر ہمیں کسی نے پیدا کیا ہے اور ہم خود بخود اس دنیا میں نہیں آگئے تو ضرور ہمارے خالق
کے اس فعل میں کوئی خاص غرض ہوگی اور ضرور ہے کہ اس نے ہماری زندگی کا کوئی مقصد
مقرر کیا ہو.اس قسم کے سوالات ہر انسان کی فطرت کم و بیش پیدا کرتی رہتی ہے.اس
جگہ میں یہ نہیں کہتا کہ فطرت ان سوالات کا کوئی جواب بھی دیتی ہے یا نہیں کیونکہ اس کی
بحث آگے آئے گی.لیکن بہر حال یہ مسلم ہے کہ فطرت ان سوالات کو ہمارے اندر
اٹھاتی ضرور رہتی ہے اور اٹھاتی بھی ایسے رنگ میں ہے کہ ہم انہیں لاتعلق کہہ کر نظر انداز
نہیں کر سکتے.بیشک ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ تحقیق کے بعد ہم یہ رائے قائم کریں کہ
فطرت کا یہ سوال بے بنیاد ہے، اور یہ کہ کوئی خدا نہیں ہے بلکہ یہ تمام کارخانہ عالم خود
بخود نیست سے ہست میں آیا اور خود بخود ہی چل رہا ہے.لیکن خوب سوچ لو کہ ان
سوالات کے پیدا ہونے کے بعد ہمیں یہ حق حاصل نہیں رہتا کہ ہم اس تحقیق میں پڑنے
سے ہی انکار کر دیں.یہی حال عقلِ انسانی کا ہے.عقل بھی خواہ بعد میں یہی فیصلہ کرے کہ کوئی خدا
نہیں ہے لیکن ان سوالات کو ضرور ہمارے سامنے بڑے زور کے ساتھ پیش کرتی ہے.بلکہ فطرت کی نسبت زیادہ وضاحت اور زیادہ تفصیل کے ساتھ پیش کرتی ہے.عقل ہمیں
بار بار ہوشیار کرتی اور کہتی ہے کہ دیکھو اور غور کرو.ایسا نہ ہو کہ تمہارا کوئی خدا ہو جس نے
تمہیں کسی خاص مقصد کے ماتحت اس دنیا میں بھیجا ہو اور تم اپنے اس خدا اور اپنی زندگی
کے اس مقصد سے غافل رہو اور غفلت کی حالت میں ہی تم پر موت آجائے.اُٹھو! اور
اگر کوئی خدا ہے تو اسے تلاش کرو.سوچو اور غور کرو کہ کیا تمہارا اس دنیا میں آنا صرف اس
لئے ہے کہ تم کھاؤ اور پیو اور اپنی جسمانی لذات پوری کرنے کی فکر میں پڑے رہو اور
جب موت کا وقت آئے تو تم مرجاؤ اور اپنے پیچھے اپنے بچوں کو چھوڑ جاؤ جو پھر تمہاری
27
Page 28
طرح دنیا کی سٹیج پر جسمانی لذات کا ڈرامہ شروع کر دیں.اپنی آنکھیں کھولو اور دیکھو کہ
کیا تم خود بخود نیست سے ہست میں آگئے ہو؟ کیا تمہارے جسموں کا یہ نہایت مفصل
اور حکیمانہ نظام اپنا خالق آپ ہی ہے؟ کیا یہ تمام کارخانہ عالم اپنے اس مدبرانہ قانون
کے ساتھ جو تم اس کے ہر حصہ اور ہر گوشہ میں کام کرتے دیکھتے ہو محض اتفاق کا نتیجہ ہے؟
اور اگر ایسا نہیں بلکہ یہ سب کچھ کسی بالا ہستی کی قدرتوں کا کرشمہ ہے تو کیا اس ہستی نے
اسے ایک کھلونے کے طور پر پیدا کیا ہے جس کا سوائے اس کے کوئی مقصد نہیں ہے کہ
اس کی لذت آشنا آنکھیں اپنی قدرت کے اس نظارہ کو دیکھیں اور جب وہ اس لذت
اور سرور سے سیر ہو جائیں تو پھر اس کا ہاتھ اس وسیع عالم کو اپنی ایک حرکت سے حرف غلط
کی طرح مٹا دے اور اس کے بعد کوئی نیا کھلونا تیار کرنے میں لگ جائے؟ کیا یہ
قرین قیاس نہیں ہے کہ انسان کی زندگی کا کوئی مقصد ہو اور اس نے اپنے دنیوی اعمال
کے متعلق کبھی کسی کے سامنے کھڑے ہو کر جوابدہ ہونا ہو؟ یہ وہ سوالات ہیں جو ہر
صحیح الدماغ انسان کی عقل بار بار اس کے سامنے پیش کرتی ہے.اب انصاف سے بتاؤ
کہ کیا یہ سوالات ایسے ہیں کہ تم ان کو لاتعلق اور غیر ضروری
قرار دیکر خاموش ہو جاؤ.میں یہ نہیں کہتا کہ تم ان سوالات کا یہ جواب دو یاوہ جواب دو کیونکہ جواب دنیا ہر شخص کی
اپنی تحقیق کے نتیجہ پر مبنی ہے جس کے متعلق خود تحقیق کرنے والا بھی پیش از وقت نہیں
کہہ سکتا کہ وہ کیا ہو گا مگر میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ جس رنگ میں یہ سوال تمہارے سامنے
آتا ہے اس کا یہ تقاضا ہے کہ تم اپنی پوری توجہ کے ساتھ اس مسئلہ کی تحقیق میں لگ جاؤ
اور اس وقت تک چین نہ لو جب تک کہ تمہاری آزاد اور دیانتدار نہ تحقیق تمہیں کسی نتیجہ
تک نہ پہنچا دے.خلاصہ کلام یہ کہ فطرت اور عقلِ انسانی ہر دو ہستی باری تعالیٰ کے سوال کو ایسے
رنگ میں ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں کہ ہم اس تحقیق میں پڑنے سے قطعاً انکار نہیں
28
Page 29
کر سکتے.کیا یہ سوال ہمارے لئے ایک لاتعلق سوال ہے کہ ہمارا کوئی پیدا کرنے والا
ہے یا نہیں؟ کیا یہ سوال ہمارے لئے ایک لاتعلق سوال ہے کہ اگر ہمیں کسی نے پیدا کیا
ہے تو وہ کون ہے؟ کہاں ہے؟ کیا کیا صفت رکھتا ہے؟ کیا یہ سوال ہمارے لئے ایک
لا تعلق سوال ہے کہ اگر ہمیں کسی نے پیدا کیا ہے تو ہماری پیدائش کی غرض کیا ہے؟ کیا یہ
سوال ہمارے لئے ایک لاتعلق سوال ہے کہ اگر ہماری پیدائش کی کوئی غرض ہے تو وہ
غرض کس طرح حاصل ہوسکتی ہے؟ اگر یہ سوالات لاتعلق نہیں ہیں اور ہر گز نہیں نہیں تو
کون عقلمند ہے جو اس تحقیق میں پڑنے سے انکار کر سکتا ہے؟
تیسر.رے درجہ پر مذہب ہے.دنیا میں جو مذاہب بھی پائے جاتے ہیں وہ سب
کے سب خدا تعالیٰ کی ہستی کا سوال ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں اور نہ صرف پیش
کرتے ہیں بلکہ انکی تعلیم کا مرکزی نقطہ ہی اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات ہے اور چونکہ
تمام مذاہب جو دنیا میں قائم ہوکر لاکھوں انسانوں کی قبولیت حاصل کر چکے ہیں اپنی
اصل کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور ان کی بنیا دالہام الہی پر ہے جو مختلف
زمانوں میں نازل ہو کر دنیا کو منور کرتارہا ہے.اس لئے باوجود اس کے کہ ان مذاہب کی
تعلیمات بعد کی انسانی دست و بُرد سے بہت کچھ حرف ومبدل ہو چکی ہوں پھر بھی چونکہ
ان کی اصل بنیاد کلام الہی پر ہے ان میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق فطرت اور عقل
کے اشارات کی نسبت بہت زیادہ وضاحت اور تفصیل اور تعیین پائی جاتی ہے گویا عقل
اور فطرت کے اجمال کو الہام نے اپنی تفسیر سے کھول دیا ہے.علاوہ ازیں مذہب
بخلاف فطرت و عقل کے ہمیں صرف یہ نہیں کہتا کہ ممکن ہے کوئی خدا ہو یا یہ کہ کوئی خدا
ہونا چاہئے بلکہ وہ معتین طور پر ہمیں یہ بتاتا ہے کہ واقعی ہمارا ایک خدا ہے جو ہمارا
خالق و مالک ہے اور جس نے ہمیں ایک خاص غرض اور مقصد کے ماتحت اس دنیا میں
بھیجا ہے.دنیا کے مختلف مذاہب کی تعلیم میں کتنا بھی اختلاف ہو اس بات پر وہ سب
29
Page 30
متفق ہیں کہ اس کا رخانہ عالم کا ایک خالق و مالک ہے جس کے قبضہ تصرف میں
ہماری جانیں ہیں اور یہ کہ ہمارے اس خالق و مالک نے ہماری زندگیوں کا ایک مقصد
مقرر کیا ہے جس کے حصول کا طریق بھی اس نے خود ہمیں بتا دیا ہے اور یہ کہ موت
انسانی زندگی کا خاتمہ نہیں ہے بلکہ موت کے بعد ایک اور زندگی ہے جس میں انسان اپنی
موجودہ زندگی کے اعمال کا ثمرہ پائیگا وغیرہ وغیرہ.مذاہب کی یہ متفقہ شہادت ہمارے
سامنے ہستی باری تعالیٰ کا سوال ایسے رنگ میں پیش کرتی ہے کہ ہم مجبور ہو جاتے ہیں کہ
اس تحقیق میں پڑ کر کسی نتیجہ پر پہنچیں.کیونکہ جو باتیں خدا تعالیٰ کے متعلق یہ مذاہب
ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں اگر وہ درست ہوں تو ہمارا اس خدا سے غافل رہنا تمام
ان نقصانات سے بڑھ کر ہے جو ہمیں اس دنیا میں ممکن طور پر پہنچ سکتے ہیں کیونکہ اس
غفلت کے یہ معنے ہیں کہ گویا ہماری ساری زندگی ہی اکارت چلی گئی اور اس خدا کو
شناخت کرنا اور اس کے ساتھ تعلق پیدا کرنا تمام ان فوائد سے بڑھ کر ہے جو ہمیں اس
دنیا میں ممکن طور پر حاصل ہو سکتے ہیں کیونکہ اس تعلق کے یہ معنی ہیں کہ جس غرض کے
لئے ہم اس دنیا میں بھیجے گئے تھے وہ غرض ہمیں حاصل ہوگئی اور ہم نے اپنی زندگی کا
مقصد یا لیا.پس خدا تعالیٰ کے متعلق تحقیق کرنے کا سوال ایک ایسا اہم سوال ہے جسے
کوئی عظمند ایک لمحہ کے لئے بھی نظر انداز نہیں کر سکتا.مذاہب کی اس متفقہ شہادت کے بعد میں اسلام کی مخصوص تعلیم کے متعلق بھی کچھ
کہنا چاہتا ہوں.سواے میرے عزیز و ! خوب کان کھول کر سن لو کہ اسلام تم سے یہ کہتا
ہے کہ تمہارا ایک خدا ہے جو تمہارا خالق و مالک ہے.یعنی جو تمہیں نیست سے ہست
میں لایا ہے اور جس کے قبضہ تصرف میں تمہاری جانیں ہیں.اسلام کہتا ہے کہ تمہارا
ایک خدا ہے جو رب ہے یعنی جو تمہاری ہر قسم کی ترقی اور بہبودی کا سامان مہیا کر کے
تمہیں کسی اعلیٰ مقام تک پہنچانا چاہتا ہے.اسلام کہتا ہے کہ تمہارا ایک خدا ہے جو رحمن
30
Page 31
ہے.یعنی وہ تمہاری تمام حقیقی ضروریات کا خیال رکھتے ہوئے خود تمہارے لئے تمہاری
ان ضروریات کو مہیا کرتا ہے بغیر اس کے کہ تم اس سے سوال کرو اور بغیر اس کے کہ تم ان
ضروریات کے پورا کرنے کے لئے کسی قسم کی محنت برداشت کرو.اسلام کہتا ہے کہ
تمہارا ایک خدا ہے جو رحیم ہے یعنی وہ تمہاری کوششوں کا بہترین ثمرہ پیدا کرتا ہے
اور کسی کوشش کو ضائع نہیں جانے دیتا.اسلام کہتا ہے کہ تمہارا ایک خدا ہے جو مالک
یوم الدین ہے.یعنی وہ تمہارے اعمال پر جزا سز ا مترتب کرتا ہے اور جب کوئی شخص
ٹھیک رستہ پر چلتا ہے تو اُسے بہتر سے بہتر انعام دیتا ہے اور جب وہ غلط راستہ پر چلتا
ہے تو اسے اس غلط طریق کے نتائج بھگتنے پڑتے ہیں تا کہ وہ ہوشیار رہے اور غافل نہ
ہونے پائے اور تاوہ اپنی زندگی کے اس مقصد کو نہ بھول جائے جو خدا نے اس کے لئے
مقرر کیا ہے کیونکہ اس نے ایک دن مر کر خدا کے سامنے کھڑے ہونا ہے.اسلام کہتا ہے
کہ تمہارا ایک خدا ہے جو غفور ہے یعنی جب تم خدا کے رستہ میں کوشش کرتے ہو تو جو
لغزشیں اور کمزوریاں تم سے سہواً سر زد ہوتی رہتی ہیں ان پر وہ پردہ ڈالتا رہتا ہے اور
تمہاری کوششوں کا خیال رکھتے ہوئے تمہیں ان کمزوریوں کے بداثرات سے بچاتا
ہے.اسلام کہتا ہے کہ تمہارا ایک خدا ہے جو تو اب ہے یعنی جب تم سے کوئی گناہ ہوتا ہے
اور پھر تم سچے دل سے اس پر نادم ہوتے ہو اور تمہاری طبیعت ایک دلی تڑپ کے ساتھ
غلط راستہ کے ترک کرنے اور ٹھیک راستہ کے اختیار کرنے کی طرف مائل ہوتی ہے اور
آئندہ کے لئے تم نیک نیتی کے ساتھ اس گناہ کے اثر کو مٹانے اور نیک اعمال کے
بجالانے کا عہد کرتے ہو تو خدا بھی تمہاری مدد کے لئے اترتا ہے اور تمہاری تو بہ کو قبول
کر کے تمہارے اس گناہ پر اپنی بخشش کا پردہ ڈال دیتا ہے.اسلام کہتا ہے کہ تمہارا ایک
خدا ہے جو قدیر ہے یعنی کوئی کام جو قدرت کے نام سے موسوم ہوسکتا ہے اس کی طاقت
سورة الفاتحه: آیت 4
31
Page 32
سے باہر نہیں ہے خواہ تمہاری نظر میں وہ کیساہی مشکل اور ناممکن نظر آئے.اسلام کہتا ہے
کہ تمہارا ایک خدا ہے جو سمیع ہے یعنی وہ ہر پکارنے والے کی پکار کوسنتا ہے اور کوئی آواز
نہیں جو اس تک نہ پہنچ سکے.اسلام کہتا ہے کہ تمہارا ایک خدا ہے جو علیم ہے یعنی کوئی
بات یا کوئی خیال یا کوئی چیز خواہ وہ پوشیدہ ہے یا ظاہر ہے اس کے علم سے باہر نہیں ہے.اسلام کہتا ہے کہ تمہارا ایک خدا ہے جو ناصر ہے یعنی تمہاری تمام ضرورتوں کے وقت اور
تمام تکلیفوں کے وقت وہ تمہاری نصرت فرماتا ہے بشرطیکہ تم اس کے ساتھ سچا تعلق پیدا
کرو.اسلام کہتا ہے کہ تمہارا ایک خدا ہے جو ازلی ابدی ہے یعنی وہ ہمیشہ سے ہے
اور ہمیشہ رہے گا اور زمانہ کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوسکتا.اسلام کہتا ہے کہ تمہارا ایک خدا ہے
جو جمیل ہے یعنی وہ تمام خوبصورتیوں اور تمام حسنوں کا مجموعہ ہے اور وہی اس قابل ہے کہ
انسان اپنی محبت کے پھول اس کے قدموں پر رکھے.اسلام کہتا ہے کہ تمہارا ایک خدا ہے
جو ودود ہے یعنی وہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے اور جو لوگ اس کے ساتھ تعلق پیدا
کرتے ہیں ان کے ساتھ وہ سب محبت کرنے والوں سے بڑھ کر محبت اور وفاداری دکھاتا
ہے.اسلام کہتا ہے کہ تمہارا ایک خدا ہے جو مکام ہے یعنی وہ اپنے تعلق رکھنے والوں کو اپنی
ہمکلامی کا شرف عطا کرتا ہے اور گو بوجہ لطیف ہونے کے وہ ان مادی آنکھوں سے نظر نہیں
آسکتا، لیکن جو لوگ اس کے عشق کی آگ اپنے سینوں میں رکھتے ہیں ان پر وہ اپنے
محبوبانہ کلام کے پانی کا چھینٹا ڈالتا رہتا ہے تا کہ وہ اس عشق کی آگ میں جل کر خاک ہی
نہ ہو جائیں.حضرت مسیح موعود بانی سلسلہ احمدیہ نے کیا خوب کہا ہے کہ ؎
میں تو مر کر خاک ہوتا گر نہ ہوتا تیرا لطف.پھر خدا جانے کہاں یہ پھینک دی جاتی غبار
عزیز و! یہ وہ خدا ہے جسے اسلام پیش کرتا ہے.میں فی الحال تمہیں یہ نہیں کہتا کہ
تم اس خدا پر ایمان لے آؤ مگر میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ اسلام کہتا ہے کہ تمہارا ایک خدا
32
Page 33
ہے جس کی یہ یہ صفات ہیں.اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ تم تلاش اور کوشش کے ساتھ اس خدا
تک پہنچ سکتے ہو.کیا تم اس تلاش اور اس تحقیق کو ایک غیر ضروری اور لاتعلق بات قرار دو
گے؟ اگر تم ایسا کرو گے تو تم یہ ثابت کر دو گے کہ تمہارے سر میں وہ جو ہر نہیں ہے جسے
عقل کہتے ہیں اور تمہارے سینہ میں دل نہیں ہے پتھر ہے.عزیز و اٹھو! اور اس خدا کی
تلاش میں لگ جاؤ.اٹھو اور اس چشمہ کی طرف بھا گو جو تمہاری زندگی کا چشمہ ہے.اُٹھو
اور اس خزانہ کی طرف بڑھو جو تمہیں دنیا و مافیہا سے غنی کر دیگا.اگر تم نے اسے پالیا تو میں
تمہیں کیا بتاؤں کہ تم نے کیا پایا ، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زبانِ مبارک سے سنو.فرماتے ہیں.تجھے سب
زور و قدرت ہے خدایا
اک مقصد کو
し
بنایا
پایا
ہر
ہر
اک عاشق نے
اک
ہے
ہمارے
دل
میں
سمایا
وہی آرام جاں
اور دل کو بھایا
وہی
جس کو کہیں
البرايا
ہوا
ظاہر
مجھ
وہ
پر بالا یا دی
بحان الـــذى اخـــــى الاعــــــادي
مجھے اُس یار
ނ
پیوند جاں ہے
وہی
جنت وہی دار الاماں
ہے
بیاں اس کا کروں طاقت کہاں ہے
ہے
محبت کا تو اک دریا رواں
کیا احساں ترے ہیں میرے ہادی
فسبحان الذي اخــى الاعــــــادي
33
Page 34
تری رحمت کی کچھ قلت نہیں
تہی اس
ނ
ہے
کوئی ساعت نہیں ہے
ہے
شمار فضل اور رحمت نہیں
مجھے
اب شکر کی طاقت نہیں
小小小小
ہے
کیا احساں ہیں تیرے میرے ہادی
فسبحـــــــان الذى اخــى الاعــــــادي
لیکن اگر بالفرض تم اس کوشش میں ناکام رہے تو خود تمہاری یہ نا کا می تمہارے
لئے اس بات کی دلیل ہوگی کہ تمہاری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے کیونکہ جو چیز اتفاق کا
نتیجہ ہے اس کا کوئی مقصد نہیں ہوسکتا.تو اس صورت میں بہر حال تم نے کسی نہ کسی کام
میں بے مقصد طور پر اپنی زندگی کے دن کاٹنے تھے.سو تم یہ سمجھ لینا کہ تم نے اپنی یہ
بے مقصد زندگی اس کوشش میں صرف کر دی کہ اس کا کوئی مقصد تلاش کیا جائے.کیا یہ
شکست ان تمام فتوحات سے بڑھ کر نہ رہے گی جو تم اپنی اس بے مقصد زندگی میں
بے مقصد طور پر حاصل کرتے ؟ مگر میں کہتا ہوں
کہ تم ہر گز نا کام نہیں رہ سکتے.تم اس
میدان میں پاک نیت اور دلی محبت اور کچی تڑپ کے ساتھ نکلو او تم دیکھو گے کہ کامیابی
کی خوشنگن ہوائیں بہت جلد تمہارا خیر مقدم کرتی ہوئی تم سے آملیں گی.کیا تم نے
حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے شعر نہیں سنے کہے
تجھے دنیا میں ہے کس نے پکارا
کہ پھر خالی گیا قسمت کا
تو پھر
مارا
قدر اس کو سہارا
کس قدر
ہے
کہ جس کا تو ہی ہے
سے پیارا
34
Page 35
خدا کے متعلق تحقیق کا طریق
اب میں نہایت اختصار کے ساتھ یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کے متعلق
تحقیق کا طریق کیا ہونا چاہئے؟ کیونکہ جب تک ہمیں یہ معلوم نہ ہو کہ کسی چیز کے متعلق
تحقیق کا صحیح طریق کیا ہے اس وقت تک کامیابی نہایت مشکل ہے.ایک غلط طریق کو
اختیار کر کے ہم اپنی ساری کوشش بلا سود ضائع کر سکتے ہیں.ایک شخص جو زمین میں
کنواں کھود کر پانی نکالنا چاہتا ہے
کبھی پانی تک نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ خاص خطہ زمین
کو منتخب کر کے خاص قواعد کے ماتحت زمین کو عمودی شکل میں کھودتا ہو انیچے نہ اتر جائے.اگر وہ زمین کو عمودی شکل میں نہیں کھودیا بلکہ سطح زمین کے متوازی کھودنا شروع کر دیگا تو
خواہ وہ دوسو میل تک کھودتا ہو اچلا جائے وہ کبھی پانی کی شکل نہیں دیکھے گا کیونکہ اس نے
پانی تک پہنچنے کا غلط طریق اختیار کیا ہے اور بعد میں اس کا یہ شکایت کرنا کہ دیکھو میں
نے اتنی محنت اور عرقریزی کی ہے اور پھر بھی مجھے پانی نہیں ملا ایک غلط اور بیہودہ عذر ہوگا
جو کسی عقلمند کے نزدیک مسموع نہیں ہوسکتا.پس معلوم ہو ا کہ صرف محنت اور کوشش کوئی
حقیقت نہیں رکھتیں جب تک کہ وہ صحیح طریق پر صرف نہ کی جائیں اور جس طرح ہم دنیا
کے تمام کاموں میں دیکھتے ہیں کہ قانون قدرت کے ماتحت ہر کام کے لئے ایک خاص
طریق مقرر ہے جس کے بغیر وہ کام سرانجام نہیں پاسکتا، اسی طرح روحانی امور میں بھی
ہر مقصد کے حصول کے واسطے ایک راستہ اور طریق مقرر ہے جسے اختیار کرنے کے بغیر
ہم اس مقصد کو حاصل نہیں کر سکتے خواہ ہم کیسی ہی محنت اور توجہ صرف کریں.اور اس
ضابطہ اور قانون کا وجود سراسر ہمارے فائدہ کے لئے ہے کیونکہ اس کے بغیر انسان کی
علمی اور عملی ترقی محال ہے.فرض کرو کہ اگر دنیا میں کوئی قانون نہ ہو اور بغیر ایک خاص
طریق پر محنت کرنے کے انسان محض خواہش سے ایک چیز کو حاصل کر سکے تو دنیا کا کیا
حشر ہو؟ کیا علم اور محنت اور کوشش اور تجربہ کی جگہ جہالت اور سستی اور کاہلی اور اتکال کا
35
Page 36
دور دوره نه شروع ہو جائے ؟ کیا عالم اور جاہل، جفاکش اور کاہل محنتی اور ست، تجربہ کار
اور اناڑی میں کوئی امتیاز اور فرق باقی رہ جائے؟ کیا انسان کی دماغی ترقی کا راستہ بالکل
مسدود نہ ہو جائے؟ کیا انسان کے اعلیٰ اخلاق کی عمارت دیکھتے دیکھتے مسمار ہو کر خاک
میں نہ مل جائے؟ خوب سوچ لو کہ یہ جو انسان کی جسمانی اور مادی اور علمی اور عملی اور
اخلاقی اور روحانی ترقی اب تمہیں نظر آتی ہے یہ ساری اسی بات کی طفیل ہے کہ دنیا ایک
قانون کے ماتحت چل رہی ہے اور ہر مقصد کے حصول کے واسطے ایک طریق مقرر ہے
جس کے بغیر وہ حاصل نہیں ہوسکتا اس قانون کو الگ کر دو اور تم دیکھو گے کہ یکانت تمام
ترقیات کا دروازہ بند ہو کر انسانی دماغ ایک منجمد پتھر کی صورت اختیار کرلے گا اور وہ
ہستی جو اشرف المخلوقات کہلاتی ہے ایک آنِ واحد میں دنیا کی حقیر ترین مخلوق سے بھی
نیچے گر جائیگی.پس اس قانون کو اپنے راستہ میں ایک روک نہ سمجھو کیونکہ یہ تو وہ پر ہیں
جو خالق کا ئنات نے علم اور عمل کی بلند چوٹیوں تک پرواز کر کے پہنچنے کے لئے تمہیں عطا
کئے ہیں.یہ وہ آفتاب ہدایت ہے جو تمہیں آئندہ ترقیات کا راستہ دکھانے کے لئے
تمہارے مہربان آقا نے چڑھا رکھا ہے.یہ وہ امتحان ہے جو عالم کو جاہل سے، عامل
کو بے عمل سے، تجربہ کار کو اناڑی سے ہمخنتی کو کاہل سے ممتاز کرنے کے لئے مقرر کیا گیا
ہے.تحقیق کے میدان میں نیت کا دخل
اب سب سے پہلے یہ جانا چاہئے کہ جب کوئی آدمی کسی کام کو شروع کرنے لگتا
ہے تو جس نیت کے ساتھ وہ اس کام کو شروع کرتا ہے وہ اس کے آئندہ طریق عمل پر
ایک بڑی حد تک اثر ڈالتی ہے.ایک ہی کام جب ایک نیت سے کیا جاتا ہے تو وہ اور
رنگ رکھتا ہے اور اور اثر پیدا کرتا ہے اور وہی کام جب دوسری نیست سے کیا جاتا ہے تو وہ
36
Page 37
بالکل دوسرے رنگ میں ظاہر ہوتا ہے اور دوسرا اثر پیدا کرتا ہے.الغرض نیت کو انسان
کے ہر کام میں بڑا دخل ہے اور نیت کا اثر انسان کے تمام کاموں میں ضرور کسی نہ کسی
صورت میں رونما ہوتا ہے اور یہ اثر کوئی فرضی اور خیالی اثر نہیں ہوتا بلکہ واقعی اور حقیقی اثر
ہوتا ہے مثلاً فرض کرو کہ ایک انسان اپنے افسر کی جس کے ماتحت وہ رکھا گیا ہے صرف
اس لئے اطاعت کرتا ہے کہ وہ اس کا افسر ہے مگر اس کے احکام میں اسے کوئی ذاتی
دلچسپی نہیں اور نہ اس افسر کے ساتھ اسے کوئی ذاتی محبت کا تعلق ہے اور نہ اُس افسر کی
لیاقت اور قابلیت کا اُس کے دل پر کوئی اثر ہے تو ایسی صورت میں اس کی اطاعت محض
ایک ضابطہ کی اطاعت ہوگی اور وہ صرف اپنے فرض منصبی کو پورا کرنے کے لئے اس
کے احکام کی تعمیل کریگا اور اُس کے کاموں میں کوئی شوق اور ولولہ اور دلچسپی نہیں نظر آئے
گی.لیکن اگر وہی شخص اپنے افسر کے ساتھ ذاتی محبت
کا تعلق رکھتا ہو اور اس کی لیاقت
اور قابلیت کا مداح ہو اور اس کے احکام میں دلچسپی رکھتا ہو تو پھر اُس کی اطاعت بالکل
ہی اور صورت میں ظاہر ہوگی اور اس کا کام کرنے کا طریق بالکل ہی نرالا ہوگا اور اس
کے ہر حرکت و سکون میں شوق اور ولولہ اور ایک ذاتی لگاؤ کا رنگ نظر آئے گا اور یہ فرق
اس لئے ہوگا کہ گو کام ایک ہی ہے یعنی اطاعت لیکن نیتیں مختلف ہیں اور نیتوں کے
اختلاف نے طریق عمل کی صورت کو بدل دیا ہے.اسی طرح خدا کے متعلق تحقیق کرنے کا سوال ہے.ایک فلسفی بھی تحقیق کرتا ہے
اور ایک سالک بھی.اور دونوں کا مقصود ایک ہی ہے کہ خدا کا پتہ لگائیں، لیکن نیتوں
میں بھاری فرق ہے.فلسفی تو اس لئے اس میدان میں قدم زن ہوتا ہے کہ اپنی عقل کی
امداد سے صحیفہ عالم پر نظر ڈال کر یہ پتہ لے کہ آیا کوئی اس کا رخانہ عالم کا بنانے والا بھی
ہے یا نہیں اور پھر جس نتیجہ پر وہ پہنچے اسے اپنی علمی معلومات کے خزانہ میں جمع کر دے
اور بس.اُسے اس سے غرض نہیں کہ خدا ہے تو رکن صفات والا ہے اور اس کا اپنے
37
Page 38
بندوں کے ساتھ کیا تعلق ہے اور بندوں کا اُس کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہئے اور اس
تک پہنچنے کا کیا ذریعہ ہے؟ کیونکہ اس کا مقصود خُدا کا تعلق نہیں بلکہ صرف یہ ہے کہ علمی
طور پر پستہ لگائے کہ کوئی اس کارخانہ عالم کا صانع بھی ہے یا نہیں.وہ اُس کے تعلق کا
خواہشمند نہیں، اس کے قرب کا شائق نہیں، اس کی دوستی کا خواہاں نہیں، اس کے دل
میں اس تک پہنچنے کی تڑپ نہیں ، اُس کی مرضی کا علم حاصل کر کے اُس کے بجالانے کا
خیال نہیں، بس ایک علمی تحقیق ہے جسے وہ پورا کرنا چاہتا ہے.دوسری طرف سالک ہے
جو خدا کے لئے سرگرداں ہے، اُس کے تعلق کا خواہشمند ہے، اُس کے قرب کا شائق
ہے، اس کی دوستی کا خواہاں ہے، اس تک پہنچنے کے واسطے بے قرار ہے اور اُس کی رضا کا
علم حاصل کر کے اُس پر کار بند ہونا چاہتا ہے اور ایک بچی تڑپ کے ساتھ اُس کی تلاش
کرتا ہے.کیا ان دونوں کی تلاش ایک رنگ کی ہوگی؟ ہرگز نہیں ہرگز نہیں.پس سب
سے پہلے یہ ضروری ہے کہ انسان اپنی نیت کو درست کرے اور ایک فلسفی کے طور پر نہیں
بلکہ ایک سالک کے طور پر اس میدان میں قدم زن ہو اور اپنے دل میں اس تڑپ اور
اس بے چینی کو پیدا کرے جو صداقت کی تلاش کے لئے ضروری ہے.دیکھو ماں کا دودھ
اس کے پستانوں میں اس طرح نہیں اترا کرتا کہ بچہ ایک معقول اور سنجیدہ صورت بنا کر
ماں کے سامنے اس بات کا اظہار کرے کہ اے میری ماں میں تیرا دودھ دیکھنا چاہتا ہوں
کہ آیا وہ میری خوراک بننے کے لئے موجود بھی ہے یا نہیں.بلکہ دودھ اس طرح اُترا
کرتا ہے کہ بچہ جب بھوک سے روتا اور بلبلاتا ہے تو اُس وقت ماں اگر اپنے آپ کو
روکنا بھی چاہے تو نہیں رک سکتی اور بے اختیار ہو کر اُس کے پستانوں سے دودھ بہنے
لگ جاتا ہے تا کہ یہ دودھ اس کے بچے کے جسم کی خوراک بن کر اُسے ہلاکت سے بچا
لے.پس خدا بھی اپنا چہرہ فلسفی پر نہیں ظاہر کرتا بلکہ اس سے دور بھاگتا ہے کیونکہ وہ
فلسفیوں کے تخیلات کا کھلونا نہیں بننا چاہتا.مگر سالک کے پاس خد ا خود آتا ہے کیونکہ
38
Page 39
وہ ماں سے زیادہ محبت کرنے والا اور وفا دار خدا ہے اور نہیں چاہتا کہ اس کی سچی تلاش
کرنے والا اُس کے متعلق تاریکی میں رہ کر ہلاک ہو جاوے.یہ بھی ایک عجیب نظارہ
ہے کہ فلسفی بھی تلاش کرتا ہے اور سالک بھی.مگر فلسفی سے خُدادُور بھاگتا ہے اور سالک
کے پاس خود بھاگتا ہو ا آتا ہے.پس اے میرے عزیز و اتم خدا کے متعلق کبھی بھی فلسفیانہ طریق تحقیق اختیار نہ
کرو کیونکہ اس طرح تم خُدا کو بھی نہیں پاسکتے اور یہ تلاش ہے بھی بے سود.کیونکہ اگر ہم
نے محض علمی طور پر خدا کے وجود کا پتہ لگا کر پھر خاموش ہو جاتا ہے تو ہمیں اس مصیبت
میں پڑنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ہم جو اپنا وقت اور توجہ اور طاقت خرچ کریں تو کیا
صرف اس لئے کہ ہمیں یہ علم حاصل ہو جائے کہ کوئی خُدا ہے یا نہیں اور بس؟ ایسا علم
ہمارے واسطے ذرہ بھر بھی مفید نہیں ہوسکتا بلکہ الٹا نقصان دہ ہوگا کیونکہ خدا کا علم پا کر پھر
اُس سے غافل رہنا ہمیں دو ہرا مجرم بنا دیگا.اسی لئے ہماری اس قسم کی کوشش کے نتیجہ
میں خُدا کبھی بھی اپنا چہرہ ہم پر ظاہر نہیں کرے گا بلکہ وہ صرف اُسی صورت میں ہم پر ظاہر
ہو گا جب وہ یہ دیکھے گا کہ ہم ایک سچی تڑپ کے ساتھ اُس تک پہنچنا چاہتے ہیں تا کہ اُس
کے قُرب کی برکات سے مستفید ہوں اور اُس کے ساتھ ذاتی تعلق پیدا کر کے اپنے
لئے اعلیٰ ترقیات کا دروازہ کھول سکیں جو انسانی زندگی کا مقصد ہے.پس سچی تڑپ اور
دلی ولولہ پیدا کرو تا تمہاری کوشش بارآور ہو اور تمہاری محنت ٹھکانے لگے.حضرت
مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں.کوئی راہ نزدیک تر راہِ محبت سے نہیں
طے کریں اس راہ سے سالک ہزاروں دشت خار
اس کے پانے کا یہی اے دوستو اک راز ہے
کیمیا ہے جس سے ہاتھ آجائے گا زر بے شمار
39
Page 40
تیر تاثیر محبت کا
خطا
جاتا نہیں
تیرانداز و نہ ہونا سُست اس میں زینہار
ہے یہی اک آگ تا تم کو بچائے آگ سے
ہے یہی پانی کہ نکلیں جس سے صدہا آبشار
اس سے خود آکر ملے گا تم سے وہ یار ازل
اس سے تم عرفانِ حق سے پہنو گے پھولوں کے ہار
نیز فرماتے ہیں ؎
وو
فلسفی کز عقل می جوید ترا دیوانه هست
دور تر هست از خردها آن راه پنهان
یعنی فلسفی جو محض عقل کے ذریعہ سے تجھے (اے خُدا ) پانا چاہتا ہے وہ یقیناً
دیوانہ ہے کیونکہ تیری پوشیدہ راہیں خشک عقل وخرد کی پہنچ سے بہت دور واقع ہوئی
ہیں.“
ایمان باللہ کے دو درجے
اس کے بعد میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ چونکہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کی ذات والا
صفات وراء الوراء ہے اور بوجہ اپنی کمال لطافت اور غیر محدود ہونے کے انسان کی مادی
آنکھوں کے احاطہ سے باہر ہے اور دوسری طرف ایمان کامل نہیں ہوسکتا اور نہ ہی وہ کوئی
زیادہ فائدہ دے سکتا ہے جب تک خدا کے متعلق انسان کم از کم اس درجہ کا یقین نہ پیدا
کرے جیسا کہ دُنیا کی مادی چیزوں کے متعلق اُسے حاصل ہے اس لئے خدا تعالیٰ نے
اپنی حکیمانہ قدرت سے یہ مقدر کر رکھا ہے کہ ایک حد تک تو انسان اللہ تعالیٰ کی طرف
قدم بڑھائے اور اُس کے بعد خدا خود انسان کی طرف نزول فرما کر اُسے اُوپر اُٹھالے.40
Page 41
گویا اللہ تعالیٰ نے ایمان کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے.ایک وہ ایمان ہے جس تک
انسان خودا اپنی عقل کی مدد سے پہنچ سکتا ہے، اور دوسرے وہ ایمان ہے جس تک مجر عقل
کی پہنچ نہیں بلکہ اس مقام کے لئے عقل کی امداد کے واسطے آسمان سے بعض اور چیزوں
کا نزول ہوتا ہے اور تب جا کر انسان اُس ایمان کو حاصل کر سکتا ہے.چنانچہ
قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:
لَا تُدْرَكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرَكُ الْاَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ -
یعنی انسانی بصارت خدا تک پہنچنے اور اس کا علم اور عرفان حاصل کرنے سے
عاجز ہے.اس لئے خدا نے یہ انتظام کیا ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو انسانی بصارت تک
پہنچاتا ہے یعنی خود اپنی طرف سے ایسا انتظام فرماتا ہے کہ انسان خدا کا علم اور عرفان
حاصل کر سکے.کیونکہ اگر خُد الطیف ہونے کی وجہ سے انسان کی ظاہری نظر کی پہنچ سے
باہر ہے تو وہ خبیر بھی تو ہے اور جانتا ہے کہ انسان کی روحانی زندگی میرے عرفان کے بغیر
ممکن نہیں.پس وہ خود اپنی طرف سے ایسے سامان پیدا کرتا ہے کہ اس کے لطیف اور
پوشیدہ ہونے کے باوجود انسان کو خُدا کا عرفان حاصل ہو سکے.گو بالا تدركه الابصار کے مقابل میں خدا کی صفت لطیف کو رکھا گیا ہے تا یہ
ظاہر ہو کہ عقل کے ذریعہ خدا کا ادراک اس لئے ناممکن ہے
کہ وہ لطیف ہے اور وهُو
يُدْرَكُ الأبصار کے مقابل میں صفت خبیر کو رکھا گیا ہے یعنی یہ کہ خدا خود اپنی شناخت کا
انتظام کرتا ہے کیونکہ وہ خبیر ہے گویا اللہ تعالیٰ کی دو مقدم الذکر صفات یعنی لا تُدْرِكُهُ
الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَار اس کی دو موخر الذکر صفات یعنی اللطیف اور الخبیر کا
علی الترتیب طبعی نتیجہ ہیں.اب ایک طرف تو قرآن شریف کی یہ تعلیم ہے جو اوپر بیان کی گئی ہے اور دوسری
سورة الأنعام - رکوع 13 آیت 4-1
41
Page 42
طرف ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن شریف میں بار بار لوگوں کو اس طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے
کہ تم اس کا ئنات اور زمین و آسمان اور دیگر مخلوقات پر غور کرو اور سوچو کہ کیا یہ سب
کارخانہ عالم مع اپنے حکیمانہ نظام کے محض اتفاق کا نتیجہ ہوسکتا ہے؟ ہرگز نہیں.بلکہ یہ
سارا نظام عالم پکار پکار کر بتا رہا ہے کہ ضرور اس کا کوئی پیدا کرنے والا ہونا چاہیے.گویا
اس طرح قرآن شریف انسان کو بار بار ہستی باری تعالے کے سوال پر غور کرنے اور
مخلوق کے مطالعہ سے خالق کی ہستی کا پتہ لگانے کی طرف متوجہ کرتا ہے اور یہ
طریق استدلال ایسا ہے کہ اس کے متعلق محض عقل ہی کافی ہے، کسی آسمانی مؤید کی
ضرورت نہیں حالانکہ آیت محولہ بالا ہمیں یہ بتاتی ہے کہ خدا کا ادراک انسانی بصارت کی
طاقت سے باہر ہے اور اسی لئے خدا خود آسمان سے ایسا انتظام فرماتا ہے کہ جس کی مدد
سے انسان خدا کا علم اور عرفان حاصل کر سکے اور یہ دونوں باتیں بظاہر ایک قسم کے تضاد
کا رنگ رکھتی ہیں مگر غور کیا جائے تو یہ کوئی تضاد نہیں بلکہ دونوں باتیں اپنی اپنی جگہ پر
درست ہیں.یعنی یہ بھی درست ہے کہ انسان عقل کی امداد سے خدا کی طرف راہ پا سکتا
ہے اور یہ بھی درست ہے کہ مجر د عقل خدا کا علم اور عرفان حاصل نہیں کر سکتی بلکہ اس کے
لئے ضروری ہے کہ خدا تعالیٰ خود آسمان سے آیات اور مؤیدات کے ذریعہ اُس کی مدد
فرمائے.اس عقدہ کا حل اس طرح پر ہے کہ جیسا کہ اوپر بیان ہوا ہے ایمان باللہ دو
درجوں میں منقسم ہے.ابتدائی درجہ وہ ہے جس کا حصول مجزر و عقل کی امداد سے ممکن ہے
اور دوسرا درجہ وہ ہے ( اور دراصل شرعی اصطلاح میں ایمان باللہ اسی درجہ کا نام ہے )
جس کا حصول مجر د عقل سے ممکن نہیں بلکہ اس کے واسطے عقل کی امداد کے لئے خدا کی
طرف سے خود خاص انتظام ہوتا ہے.پہلا درجہ ایمان کا جو عقل سے حاصل ہوسکتا ہے
وہ صرف اس قدر ہے کہ ہم عقلی دلائل سے اس نتیجہ پر پہنچ جائیں کہ اس کائنات عالم کا
کوئی خالق و مالک ہونا چاہئے کیونکہ یہ سب کچھ جو ہم زمین و آسمان میں دیکھتے ہیں بغیر
42
Page 43
کسی خالق و مالک کے خود بخود کسی اتفاق کا نتیجہ نہیں ہوسکتا وغیر ذالک.اور دوسرا درجہ
ایمان کا یہ ہے کہ واقعی وہ خالق و مالک موجود بھی ہے اور اُس کی یہ یہ صفات ہیں اور اس
تک انسان اس طرح پہنچ سکتا ہے.گویا ایک مرتبہ ہونا چاہیے کا ہے اور دوسرا ہے
کا.6
اب خوب سوچ لو کہ مجر وعقل کبھی بھی ہمیں ” ہے“ کے مرتبہ تک نہیں پہنچا سکتی
بلکہ اس کا کام صرف اس قدر ہے کہ وہ خدا کے متعلق ہونا چاہئے“ تک کا یقین ہمارے
اندر پیدا کر دے.گویا اگر غور کیا جائے تو مجر و عقل ہمارے اندر خدا کے متعلق ایمان نہیں
پیدا کر سکتی مگر ہمیں ایمان کے لئے تیار کر سکتی ہے.وہ ہمیں خدا دکھا نہیں سکتی مگر خدا کی
طرف دُور سے اشارہ کر سکتی ہے.وہ ہمیں خُدا سے ملا نہیں سکتی مگر خدا کی ملاقات کا
دروازہ ہمارے لئے کھول سکتی ہے.وہ ہمارے اندر اطمینان نہیں پیدا کر سکتی لیکن
اطمینان حاصل کرنے کے لئے جس تڑپ کی ضرورت ہے وہ ہمیں عطا کرسکتی ہے.وہ
ہمارے دلوں میں خدا کے متعلق یقین نہیں پیدا کر سکتی لیکن یہ یقین ضرور پیدا کر سکتی ہے
کہ کوئی خُدا ہونا چاہئے.اس سے آگے لے جانا مجزر د عقل کا کام نہیں کیونکہ اس مقام پر
پہنچ کر عقل کے سامنے لا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ ( یعنی بصارت انسانی خدا کا ادراک نہیں
کر سکتی ) کا آہنی دروازہ روک ہو جاتا ہے جہاں فرشتوں کا پہرہ ہے اور جب تک عقل
کے پاس خدائی دربار کا خاص پاسپورٹ نہ ہو وہ آگے نہیں گزر سکتی.یا یوں سمجھو کہ عقل
کی محدود نظر ” ہونا چاہئے کے مقام تک پہنچ کر رک جاتی ہے اور پھر جب تک خدا کی
طرف سے اُسے ایک خاص عینک نہ عطا کی جائے وہ آگے نہیں گزر سکتی.لیکن جب
اُسے یہ خدائی عینک مل جاتی ہے تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ گویا تمام پردے جو رستہ میں روک
ہوتے ہیں پھٹ جاتے ہیں اور وہی نظر جو اس سے قبل در ماندہ ہوکر واپس لوٹ لوٹ
جاتی تھی اب سیدھی خالق ہستی کے منور چہرہ پر پڑنی شروع ہوتی ہے اور جوں جوں
43
Page 44
انسان قریب ہوتا جاتا ہے اس کا یہ منظر زیادہ صاف ہوتا جاتا ہے اور علم اور عرفان ترقی
کرتے جاتے ہیں مگر اس قرب کی کوئی حد نہیں اور نہ اس علم و عرفان کی کوئی انتہا ہے
کیونکہ خدا غیر محدود ہے اور غیر محدود کا عرفان بھی محدود نہیں ہوسکتا.اسی لئے رَبِّ
زِدْنِي عِلماً ( یعنی اے میرے رب ! میرے علم میں ترقی دے) کی دُعا جس طرح
زید و بکر کے منہ سے نکلتی ہے اُسی طرح حضرت سرور کائنات خاتم الرسل صلی اللہ علیہ وسلم
کے منہ سے بھی نکلتی تھی جس کی زبان پر خدا نے یہ الفاظ جاری فرمائے کہ اَنَا سَيِّدُ وُلدِ
ادَمَ وَلَا فَخْرَ ( یعنی میں تمام بنی آدم کا سردار ہوں مگر میں اس کی وجہ سے تکبر نہیں
کرتا ) اور جس کے متعلق خدا نے فرمایا کہ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنِي
(یعنی ہمارا یہ بندہ ہم سے قریب ہوا اور اتنا قریب ہوا کہ گویا ہم میں نہاں ہو گیا ) اللهم
صل علی محمد و بارک وسلم.مگر افسوس کہ اکثر لوگ جب ایمان کے ابتدائی مرتبہ کو حاصل کرتے ہیں تو یہ
سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ بس ہم نے جو کچھ پانا تھا پالیا.اور اس سے بھی زیادہ
قابل افسوس بات یہ ہے کہ دُنیا میں بیشتر حصہ ان لوگوں کا ہے جو اگر خدا تعالیٰ کے متعلق
توجہ کرتے ہیں تو ” ہونا چاہئے“ کے مرتبہ سے آگے نہیں گذرتے اور صرف اسی مقام
تک پہنچ کر یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ ہم نے خُدا کو پالیا حالانکہ گو اس میں شک نہیں ہے
کہ ” ہونا چاہئیے کا مرتبہ ” ہے" کے مرتبہ کے لئے بطور ایک زینہ کے ہے اور
عالم روحانیت میں انسان کو ابتدائی بیداری اسی مقام میں پہنچ کر حاصل ہوتی ہے لیکن
اگر اس مقام پر پہنچ کر انسان آگے قدم بڑھانے سے رک جائے اور اسی کو اپنا منتہی اور
مقصود سمجھنے لگ جائے تو یہی حالت اُس کے واسطے نہایت خطرناک اور مہلک بھی ثابت
ہو سکتی ہے اور بسا اوقات اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے قدموں پر واپس لوٹ کر
سورة طه ايت 115
سورة النجم - آيات 10-9
44
Page 45
ہمیشہ کے لئے دہریت کے تاریک گڑھے میں گر جاتا ہے اور خُد اکو تلاش کرتا کرتا خدا کا
منکر ہو بیٹھتا ہے اور اسی انکار کی حالت میں اُس پر موت آجاتی ہے کیونکہ جب وہ دیکھتا
ہے کہ باوجود اس قدر کوشش اور سعی کے وہ خدا کو نہیں پاسکا اور زیادہ سے زیادہ اس خیال
تک پہنچ سکا ہے کہ کوئی خُدا ہونا چاہئے تو آخر آہستہ آہستہ مایوسی اُس پر غلبہ پانا
شروع
کرتی ہے اور بالآخر وہ اپنی عقل کی ہدایت کو ایک دھو کہ خیال کر کے خدا تعالے کا منکر
ہو جاتا ہے.اس کی ایسی ہی مثال سمجھنی چاہئے جیسے کہ کوئی شخص کسی کمرے کے دروازہ کو
اندر سے بند پائے اور اس سے وہ یہ استدلال کرے کہ اس کمرہ کے اندر ضرور کوئی شخص
ہونا چاہئے ورنہ اس کا دروازہ خود بخود اندر سے بند نہیں ہوسکتا تھا لیکن وہ ایک بہت بڑا
لمبا عرصہ اس دروازہ کے سامنے کھڑا رہے اور اس کو کھٹکھٹائے اور آواز میں دے اور شور
کرے لیکن وہ دروازہ اُس کے لئے نہ کھولا جائے اور نہ ہی اُسے اندر سے کوئی آواز
آئے تو آہستہ آہستہ اس کے دل میں شکوک پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے کہ ممکن ہے
یونہی کسی نامعلوم بات کے نتیجہ میں یہ دروازہ اندر سے بند ہو گیا ہو یا یہ کہ بند کر نیوالا اندر
ہی مر چکا ہو وغیرہ وغیرہ اور بالآخر ایک وقت اُس پر ایسا آئے گا کہ وہ بالکل مایوس
ہو جائے گا اور اس یقین سے واپس لوٹ جائے گا کہ کمرہ کے اندر کوئی آدمی نہیں ہے.پس خدا کے متعلق بھی اگر ” ہونا چاہئے والا ایمان ہے‘ والے ایمان کی طرف
راہنمائی نہیں کرتا تو اس کا آخری نتیجہ بھی سوائے مایوسی اور دہریت کے اور کوئی نہیں.اور جولوگ غور کا مادہ رکھتے ہیں اُن کے لئے یہ ناممکن ہے کہ اس مقام تک پہنچ کر رک
جائیں.وہ یا تو آگے قدم بڑھائیں گے اور یا کچھ عرصہ کے بعد مایوس ہو کر واپس لوٹ
جائیں گے لیکن افسوس کہ دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں ( بلکہ انہی لوگوں کی کثرت
ہے ) کہ جن کی آنکھوں پر ایسا غفلت کا پردہ چھایا ہوتا ہے کہ وہ اس مقام تک پہنچ کر جو
ہونا چاہئے“ کا مقام ہے یہ تسلی پا جاتے ہیں کہ ہم خدا تک پہنچ گئے ہیں اور جو کچھ ہم
45
Page 46
نے پانا تھا پا لیا ہے.گویا اپنی نادانی اور غفلت اور جہالت سے وہ خدا تعالیٰ کے متعلق
اس حد تک عرفان کافی سمجھتے ہیں کہ اس کارخانہ کا کوئی خالق ہونا چاہئے اور اُن کا ذہن
پوری بیداری کے ساتھ اس بات کی طرف جاتا ہی نہیں کہ اگر کوئی خالق ہونا چاہئے تو وہ
ہے بھی یا نہیں اور اگر ہے تو کون ہے.کہاں ہے.کیا کیا صفات رکھتا ہے.اس کے
ساتھ ہم کس طرح تعلق پیدا کر سکتے ہیں اور ہمیں کس طرح معلوم ہوسکتا ہے کہ اُس کا
بھی ہمارے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ ایسے لوگ نہ تو آگے قدم بڑھانے کی فکر کرتے ہیں
اور نہ ہی اپنی اس جھوٹی تسلی کی وجہ سے پیچھے لوٹتے ہیں اور ان کی موت اسی حالت میں
اُن کو آلیتی ہے کہ وہ راستہ پر ہی بیٹھے ہوئے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم منزل مقصود تک
پہنچ چکے ہیں.آجکل خدا کے ایمان کا دم بھرنے والے اکثر لوگ اسی قسم میں داخل
ہیں.آہ! بد قسمت انسان ! تُو نے عقل کے مذھم اور کمزور چراغ سے روشنی پا کر ایک حد
تک راستہ طے کیا اور پھر جب وہ وقت آیا کہ تو خدا کے رُوحانی سورج کی زبر دست
کرنوں کی روشنی میں داخل ہو کر خدا کی طرف گرتا پڑتا نہیں بلکہ ) شوق سے دوڑتا
بھاگتا ہو اقدم بڑھائے اور ابتداء دور سے اپنے آقا و مولی کو شناخت کر کے پھر اس کے
قریب ہوتا چلا جائے حتی کہ اُس کی مقدس صفات تجھے ماں کی گود کی طرح اپنے اندر
ڈھانک لیں تو تو یہ خیال کر کے کہ میں نے خُدا کو پالیا ہے وہیں اپنی عقل کے مدھم
چراغ کی کمزور روشنی میں راستہ سے ایک طرف ہٹ کر بیٹھ گیا اور وہیں اپنی زندگی کے
دن گزار دیئے.میں نہیں سمجھ سکتا کہ تیرا دل جس کے اندر خالق فطرت نے یقین کی
ایسی پیاس ودیعت کر رکھی ہے جو بغیر حقیقی اطمینان کے تسلی نہیں پاتی اور جس میں
عشق و محبت کی وہ آگ بھڑکائی گئی ہے جو بغیر خدا کی طرف سے محبت کا چھینٹا پڑنے کے
نہیں بجھتی کس طرح بغیر اپنا مقصود حاصل کرنے کے تسکین پاسکتا ہے؟ تو اگر دھو کہ نہیں
دیتا تو یقیناً دھو کہ خوردہ ہے اور یاد رکھ کہ بعض صورتوں میں دھوکہ کھانا بھی انسان کو
46
Page 47
مجرموں کی صف میں کھڑا کر دیتا ہے.پس خدا سے ڈر اور راستہ میں بیٹھا رہ کر اپنی
ہلاکت اور دوسروں کی گمراہی کا موجب نہ بن.احتیاطی دلیل
خدا کی ہستی کے متعلق عقلی دلائل
اب میں مختصر طور پر چند وہ عقلی دلائل بیان کرتا ہوں جن سے ہمیں خدا تعالیٰ کی
ہستی کا پتہ چلتا ہے اور جیسا کے اوپر بیان ہوا ہے یہ دلائل ہمیں صرف ” ہونا چاہیئے
کے مقام تک لے جاتے ہیں اور اس سے اوپر جانے کے واسطے ہمیں اور قسم کے دلائل
کی ضرورت ہوگی جو انشاء اللہ بعد میں بیان کئے جائیں گے.مگر ان عقلی دلائل کے
بیان کرنے سے
قبل میں ایک ایسی دلیل بیان کرنا چاہتا ہوں جو محض ایک احتیاطی دلیل
ہے.یہ بات مخفی نہیں ہے کہ بعض اوقات ہم دنیا میں ایک کام محض اس لئے اختیار کرتے
ہیں کہ اس کا اختیار کرنا گو و یسے کسی معقول بنا پر ضروری نہ ہومگر احتیاط کے پہلوکومدنظر
رکھ کر ضروری ہوتا ہے.مثلاً اگر ہم رات کے وقت کسی جنگل بیابان میں ڈیرہ لگاتے ہیں
تو بعض اوقات باوجود اس علم کے کہ جنگل کے اس حصہ میں کسی درندہ یا چور چکار کا
اندیشہ نہیں ہے ہم احتیا طا رات کے وقت پہرہ کا انتظام کر لیتے ہیں اس خیال سے کہ گو
بظاہر کوئی خطرہ نہیں ہے لیکن ممکن ہے کہ کوئی خطرہ کا احتمال پیدا ہو جائے اور اُس وقت ہم
بے دست و پا ہوں اور ہماری عقل ہمیں یہی مشورہ دیتی ہے کہ اگر تو کوئی خطرہ پیدا نہ ہوا
تو اس صورت میں پہرہ کا انتظام ہمارے لئے نقصان دہ نہیں اور اگر کوئی خطرہ پیدا ہو گیا
تو لاریب پہرہ کا انتظام ہمیں بہت فائدہ پہنچا سکتا ہے.الغرض بسا اوقات ہم ایک کام
محض احتیاطی پہلو سے اختیار کرتے ہیں اور ساری دنیا اس بات پر متفق ہے کہ اس قسم
47
Page 48
کے احتیاطی انتظام بھی ضروری اور مفید ہوتے ہیں.اب اس اصل کے ماتحت ہم ہستی باری تعالیٰ کے اصول پر نظر ڈالتے ہیں تو
ہماری عقل یہی فیصلہ کرتی ہے کہ خدا تعالیٰ پر ایمان لے آنا انکار کر دینے سے بہر حال
زیادہ امن اور زیادہ احتیاط کا طریق ہے.اگر تو کوئی خدا نہیں اور یہ سارا کارخانہ عالم
محض کسی اتفاق کا نتیجہ ہے تو ظاہر ہے کہ پر ایمان لانا ہمارے واسطے کسی طرح
نقصان دہ نہیں ہوسکتا اور اگر کوئی خدا ہے تو ہمارا یہ ایمان لاریب سراسر مفید اور فائدہ مند
ہوگا.آخر اس سوال کے دو ہی جواب ہو سکتے ہیں تیسرا تو کوئی ممکن نہیں.یا یہ کہ ساری
دنیا خود بخود اپنے آپ سے ہے اور خود بخود ہی چل رہی ہے اور خدا ( نعوذ باللہ ) ایک
خیال باطل ہے اور یا اس کا ایک خالق و مالک ہے جس نے اسے پیدا کیا ہے اور جو اسے
چلا رہا ہے.ان کے علاوہ تیسرا کوئی پہلو ہماری عقل تجویز نہیں کرتی.اب اگر ہم خدا کا
انکار کر دیتے ہیں تو یہ امکان کہ ممکن ہے کہ کوئی خدا ہو ہمارے لئے خطرناک احتمالات
پیش کرتا ہے اور اگر ہم خدا پر ایمان لے آتے ہیں تو یہ امکان کہ ممکن ہے کوئی خدا نہ ہو
ہمارے لئے قطعاً کوئی خطرناک احتمال پیش نہیں کرتا فَأَيُّ الْفَرِيْقَيْنِ اَحَقُّ بِالَا مِّنِ
إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُون " یعنی " سوچو کہ کون گروه امن کے زیادہ قریب ہے، انکار کرنے
والا یا ایمان لانے والا ؟ پس ثابت ہوا کہ خدا کو مان لینا ہی احتیاط کا رستہ ہے کیونکہ
اس میں کسی قسم کے نقصان کا احتمال نہیں ہے اور انکار کر دینے میں نقصان کا احتمال موجود
ہے.کہتے ہیں کسی نے حضرت علیؓ سے پوچھا تھا کہ خدا کی ہستی کا کیا ثبوت ہے؟
انہوں نے یہ دیکھکر کہ سائل ایک سیدھا سادہ آدمی ہے اسے یہی جواب دیا کہ دیکھو
تمہارے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ اگر تو کوئی خدا نہیں ہے تو مان لینے والے اور نہ ماننے
سورة الأنعام - آيت 82
48
Page 49
والے سب برابر ہیں.کسی کا کوئی نقصان نہیں ہے اور اگر خدا ہے تو خوب یا درکھو کہ انکار
کرنے والے کی خیر نہیں.اُس شخص کی اسی دلیل سے تسلی ہو گئی اور اُس نے آگے کوئی
سوال نہ کیا.واقعی اگر تو کوئی خدا نہیں ہے تو ہمیں مان لینے میں حرج کیا ہے؟ وہ کونسی چیز
ہے جو خدا کو مان کر ہمیں چھوڑنی پڑتی ہے؟ موٹی باتوں میں زنا قتل.چوری.ڈاکہ.جُھوٹ.دھو کہ.فریب وغیرہ ہی وہ باتیں ہیں جو ایمان باللہ تم سے چھڑاتا ہے اور یہ وہ
باتیں ہیں جن کو خود تمہاری فطرت اور تمہاری عقل اور تمہاری حکومت بھی تم سے چھڑا رہی
ہیں.پس خدا پر ایمان لے آنے سے تمہارا نقصان کیا ہوا؟ یہ ایمان تمہاری کسی جائز
خواہش کے جائز طور پر پورا ہونے میں قطعا کوئی روک نہیں ہوتا.تم جائز طور پر
کھاؤ، پیو.سوؤ، جاگو.اُٹھو بیٹھو.کھیلو، کو دو.پڑھو، لکھو.دنیا کے کام کرو.مال کماؤ.دوستیاں لگاؤ.بیویاں کر کے گھر بساؤ اولاد پیدا کرو.تمہارا خدا پر ایمان لانا ہرگز تمہیں
کسی کام سے نہیں روکتا.بلکہ وہ صرف ایسے کاموں سے منع کرتا ہے جو تمہاری ذات
کے لئے یا دوسروں کی ذات کے لئے ضرر رساں اور نقصان دہ ہیں اور ایسے کاموں سے
باز رہنا خود تمہاری فطرت اور عقل اور قانون تمدن اور قانونِ سیاست کا بھی تقاضا ہے.پس تمہیں خدا پر ایمان لانے میں نقصان کیا ہے؟ اور اگر کہو کہ ہم کیوں بلا ثبوت خدا کو
مانیں تو میں کہتا ہوں کہ جس طرح تم دنیا میں بیشمار احتیاطی تجاویز کیا کرتے ہواُسی
طرح کی ایک تجویز اسے بھی سمجھ لو.بہر حال جب مان لینے میں فائدہ کا احتمال ہے اور
نقصان کا احتمال نہیں اور انکار کر دینے میں فائدہ کا کوئی احتمال نہیں اور نقصان کا احتمال
ہے تو پھر خود سوچ لو کہ کونسا طریق امن اور احتیاط کے زیادہ قریب ہے؟ ظاہر ہے کہ عموماً
خدا کا انکار کرنے والے صرف اس لئے انکار کرتے ہیں کہ اُن کے نزدیک خدا کی ہستی
کا کوئی ثبوت نہیں اور اس لئے انکار نہیں کرتے کہ خدا کے نہ ہونے کا ان کے پاس کوئی
ثبوت ہے.پس اس صورت میں احتیاطی پہلو کو مد نظر رکھ کر ہر عظمند کی عقل یہی فتویٰ
49
Page 50
دے گی کہ خُدا پر ایمان لانا ہی اقرب بالامن ہے.خلاصہ کلام یہ کہ اگر تو خدا کوئی نہیں تو
سب برابر ہوئے.ہمیں اُس پر ایمان لانے میں کوئی نقصان نہیں.اور اگر خدا ہے تو
ماننے والے فائدہ میں رہے اور انکار کرنے والے اپنا انجام آپ سوچ لیں.اگر کوئی شخص یہ شبہ پیدا کرے کہ ایسا ایمان کس کام کا ہے جس کی بنیاد حقیقت پر
نہیں بلکہ محض احتیاطی پہلو پر ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بیشک ایسا ایمان حقیقی ایمان
نہیں کہلاسکتا لیکن نہ ہونے سے ضرور بہتر ہے اور کم از کم ایسا شخص اس قسم کے ایمان کی
وجہ سے خدا کی طرف کچھ نہ کچھ متوجہ رہے گا اور یہ توجہ اُسے حقیقی ایمان کے حصول میں
بطور زمینہ کے کام دے سکے گی.علاوہ ازیں یہ ایمان گیا ہے گاہے نیک اعمال کے لئے
بھی محرک ہوسکتا ہے.بہر حال خواہ یہ ایمان کیسا ہی ناقص ہو، نہ ہونے سے یقینا بہتر
ہے اور جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں ایسا ایمان اس احتیاطی دلیل کے نتیجہ میں بھی پیدا ہوسکتا
ہے جو ہم نے اوپر بیان کی ہے اور کوئی وجہ نہیں کہ ہم اس سے محروم رہیں.فطری دلیل
اس کے بعد میں اصل دلائل کو شروع کرتا ہوں.سب سے پہلی دلیل جو
ہستی باری تعالیٰ کے متعلق میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ فطری دلیل ہے.خدا تعالیٰ کے
متعلق تحقیق کی ضرورت کے مضمون پر بحث کرتے ہوئے میں نے بتایا تھا کہ ہماری
فطرت خود اس سوال کو ہمارے اندر پیدا کر رہی ہے کہ آیا کائناتِ عالم کا کوئی
خالق و مالک ہے یا نہیں ؟ اس لئے ہم اس سوال کو نظر انداز نہیں کر سکتے.اب میں یہ بتانا
چاہتا ہوں کہ فطرتِ انسانی یہ سوال پیدا کر کے خاموش نہیں ہو جاتی بلکہ اس کا جواب بھی
دیتی ہے اور وہ لوگ جو فطرت کی آواز سُننے کے عادی ہیں وہ اس آواز کو بھی سنتے ہیں اور
سن سکتے ہیں.فطرت سے کیا مراد ہے؟ اس سوال کا جواب بھی اچھی طرح سمجھ لینا
50
Page 51
ہئے کیونکہ جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ فطرت کہتے کسے ہیں اُس وقت تک فطرت کی
آواز کے معنے سمجھنا بھی مشکل ہیں.سو جاننا چاہئے کہ فطرت ایک عربی لفظ ہے جو فطر
سے نکلا ہے.چنانچہ کہتے ہیں فُلانٌ فَطَرَ الاَ مْرَأَى اِخْتَرَعَهُ وَابْتَدَءَ هُ وَانْشَاءَهُ
یعنی جب یہ کہا جائے کہ فلاں شخص نے فلاں امر فطر کیا تو اس سے مُراد یہ ہوتی ہے کہ
اس نے فلاں امر کو جو پہلے موجود نہ تھا بنایا اور اس کی ابتداء کی اور اُسے نیست سے ہست
میں لاکر زندگی کے میدان میں بلند ہونے کے قابل بنا دیا.چنانچہ اسی بنا پر لغت والوں
نے فطرت کے معنے یہ لکھے ہیں کہ : - الصفة التي يتصف بها كلّ مولود في
اوّل زمان خلقتہ یعنی فطرت ان صفات کا نام ہے جو ہر بچے میں اُس کی ابتداء
خلقت کے وقت ودیعت کی جاتی ہیں.“
اس تعریف کے مطابق فطرتِ انسانی سے وہ صفات وخواص مراد ہونگے جو
بیرونی اثرات کے نتیجہ میں نہیں پیدا ہوئے بلکہ خلقی اور طبعی طور پر انسان کے اندر مرکوز
کئے گئے ہیں تا وہ انکے ذریعہ اپنے واسطے ترقیات کا دروازہ کھول سکے.ظاہر ہے کہ ہر
چیز بعض ایسے خواص اپنے اندر رکھتی ہے جو اسکے حواس طبعی کہلاتے ہیں.انہی خواص کا
مجموعہ فطرت ہے.یہ خواص اور صفات بیرونی اثرات کے ماتحت آکر دب جاتے ہیں
یا چمک جاتے ہیں.اور اسی پر کسی ہستی کی ترقی اور تنزل کا دارو مدار ہے اور ہر شخص اپنے
اندر غور کر کے اس بات کا پتہ لگا سکتا ہے کہ اس کے فطری خواص کس راستہ پر چل رہے
ہیں.مثلاً راست گفتاری انسان کا ایک فطری جذبہ ہے یعنی انسان کا یہ فطری خاصہ ہے
کہ وہ وہی بات منہ پر لائے جو واقعہ کے مطابق ہے اور ہر بچہ ابتداء اسی فطری خاصہ
کے مطابق اپنا رویہ رکھتا ہے.لیکن بعض اوقات جب وہ دیکھتا ہے کہ اُس کے کسی فعل پر
اُس کے ماں باپ ناراض ہوتے ہیں اور وہ فعل کسی وجہ سے اُسے مرغوب اور پسند خاطر
ہوتا ہے تو اس کے دل میں اس فعل کے کرنے کی خواہش زور پکڑتی ہے لیکن وہ اپنے
51
Page 52
والدین کی ناراضگی سے ڈر کر اُن سے اپنے اس فعل کو چھپانا چاہتا ہے اور یہ پہلا پردہ
ہوتا ہے جو اُس کی فطرت پر پڑتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ وہ اس بات کے لئے بھی تیار
ہو جاتا ہے کہ کام تو وہی کرتا ہے جو اسے پسند ہوتا ہے لیکن والدین سے اُسے نہ صرف
چھپاتا ہے بلکہ اُن کے دریافت کرنے پر خلاف واقعہ بیان دے دیتا ہے کہ میں نے یہ
کام نہیں کیا اور اس طرح اس کا یہ فطری جذبہ کہ ہر معاملہ میں سچی سچی بات کہہ دینی
چاہئے ،ظلمت کے پردوں کے نیچے دیتا چلا جاتا ہے حتی کہ وہ وقت آتا ہے کہ جب وہ
گویا اپنی فطرت
کو بالکل ہی بھول جاتا ہے.ایسے ہی موقعہ پر کہتے ہیں کہ فلاں شخص کی
فطرت مرچکی ہے حالانکہ دراصل فطرت بھی نہیں مرتی بلکہ صرف بیرونی اثرات کے
نیچے دب کر مستور و محجوب ہو جاتی ہے.اسی طرح دوسرے فطری جذبات کا حال ہے.مثلاً محبت.نفرت حلم غضب عفو.انتقام - شجاعت.خوف.عفت شہوت.ترقی
کی خواہش.تنزل سے نفرت اور اسی قسم کے دوسرے جذبات فطرت انسانی کے اندر
طبعی طور پر مرکوز ہیں لیکن بیرونی اثرات ان کو دباتے یا چمکاتے رہتے ہیں.یعنی کبھی تو یہ
خواص افراط کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اور کبھی تفریط کی طرف جھک جاتے ہیں اور
کبھی حد اعتدال کے اندر اندر رہتے ہیں.ان حالات میں فطرت کی آواز کا سوال ایک بہت نازک اور مشکل سوال ہے
اور سوائے اس شخص کے جس کے فطری جذبات اعتدال کی حالت میں ہوں دوسرے
لوگ خود اپنی فطرت کے متعلق بھی عموماً دھوکا کھا جاتے ہیں لیکن بایں ہمہ اس میں شک
نہیں کہ فطرت ایک حقیقت ہے جس سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا اور ہر فطری خاصہ کا
ایک تقاضا ہوتا ہے جو اُس کی آواز کہلاتا ہے.مثلاً راست گفتاری ایک فطری خاصہ ہے
اور اس خاصہ کا یہ تقاضا ہے کہ جب کوئی موقعہ پیش آئے تو جو بھی واقعہ ہے اُس کے
مطابق انسان اپنا بیان دے.نہ کوئی بات خلاف کہے اور نہ کوئی بات زیادہ کرے اور
52
Page 53
یہی تقاضا فطرت کی آواز کہلائے گا چنانچہ اس فطری آواز کو زندہ رکھنے کے واسطے
قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:
فَاقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا
یعنی اے انسان! تو اپنی توجہ اعتدال کی حالت میں رکھتا کہ تو اس فطری حالت
پر قائم رہ سکے جس پر خدا نے انسان کو پیدا کیا ہے.اب ہر شخص اپنے اندر غور کرے کہ کیا اس کی فطرت ہستی باری تعالیٰ کے متعلق
کوئی آواز پیدا کر رہی ہے یا نہیں ؟ کیا وہ جب الگ ہو کر اپنے دل سے یہ سوال کرتا ہے
کہ کیا میر اوجود محض ایک اتفاق
کا نتیجہ ہے یا کہ مجھے کسی بالا ہستی نے پیدا کیا ہے تو اُسے
اس سوال کے جواب میں بغیر اس کے کہ وہ عقلی دلائل کے رستہ پر پڑ کر سوچ بچار کے
نتیجہ میں کوئی رائے قائم کرے کوئی فطری آواز سنائی دیتی ہے یا نہیں؟ قرآن شریف
فرماتا ہے:.وَإِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَ أَشْهَدَ هُمْ عَلَى
اَنْفُسِهِمْ ، اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ، قَالُوْا بَلَى شَهِدْنَا ۚ أَنْ تَقُوْلُوْا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا
كُنَّا عَنْ هَذَا غَفِلِيْنَ.یعنی اللہ تعالیٰ نے جب بنی نوع انسان کی نسل کو چلایا تو خود اُن سے اُن کے
نفسوں پر شہادت کی اور پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں ؟ انہوں نے جواب دیا کہ
ہاں بیشک تو ہمارا رب ہے.اور یہ خدا نے اس لئے کیا کہ تا قیامت کے دن تمہیں یہ عذر
نہ رہے کہ ہمیں تو خدا کے متعلق کچھ پتہ ہی نہیں لگا.اس آیت کریمہ سے یہی مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو جس
طرح دوسرے خواص وصفات اس کے اندر ودیعت کئے اسی طرح یہ بات بھی اس کی
ل سورة الروم - آیت 31
53
سورۂ الاعراف آیت 173
Page 54
فطرت میں رکھدی کہ تیرا ایک خالق و مالک ہے جس سے تجھے غافل نہ رہنا چاہئے اور
خدا نے ایسا اس لئے کیا کہ تا قیامت کے دن کسی کو یہ عذر نہ رہے کہ ہم تو لاعلمی کی حالت
میں ہی گزر گئے ورنہ ہم ضرور خدا کی طرف توجہ کرتے.غرض دوسرے فطری خواص کی
طرح یہ بھی ایک فطری خاصہ ہے کہ ہم خود بخود نہیں ہیں بلکہ ایک بالا ہستی کی قدرت خلق
سے عالم وجود میں آئے ہیں اور ہر شخص جس کی فطرت بیرونی اثرات کے نیچے دب
کر مستور و مجوب نہیں ہوچکی اپنے اندر ضرور اس آواز کو گاہے گاہے اٹھتا ہو اپائے گا کہ
میرا ایک پیدا کرنے والا ہے.بلکہ جولوگ کسی وجہ سے اپنی فطرت کو ظلمت اور غفلتوں
کے پردہ کے نیچے دفن کر چکے ہیں اُن پر بھی بعض حالات ایسے آجاتے ہیں کہ اُن کی
سوئی ہوئی فطرت اچانک جاگ کر ان کے کان میں یہ آواز پیدا کر دیتی ہے.چنانچہ
بسا اوقات دیکھا گیا ہے کہ ایک دہر یہ بھی سخت اور اچانک مصیبت کے وقت میں
رام رام یا اللہ اللہ پکار نے لگ جاتا ہے.کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ عادت کا نتیجہ ہے لیکن
میں کہتا ہوں کہ عادت تو حالات کے نتیجہ میں پیدا ہو ا کرتی ہے.ایک شخص جو خدا کا منکر
ہے اور سالہا سال سے انکار پر قائم چلا آتا ہے بلکہ خدا پر ایمان لانے والوں کے خلاف
تقریر وتحریر کے ذریعہ زہر اُگلتا رہتا ہے اس کے متعلق نہیں کہا جاسکتا کہ اُس کا خدا کو
پکارنا کسی عادت کا نتیجہ ہوسکتا ہے.اُس کی عادت تو خدا کو بُرا بھلا کہنا اور گالیاں دینا ہے
نہ کہ خدا کو مدد کے واسطے پکارنا.پس ایک سالہا سال کے پختہ دہریہ کے منہ سے اچانک
مصیبت کے وقت میں رام رام یا اللہ اللہ کالفظ نکلنا فطرت کی آواز کے سوا اور کسی چیز کا
نتیجہ نہیں ہو سکتا.دراصل مصیبت بھی ایک زلزلہ کا رنگ رکھتی ہے اور جس طرح زلزلہ
بعض اوقات دبی ہوئی چیزوں کو باہر نکال پھینکتا ہے اسی طرح مصائب کا اچانک زلزلہ
بھی بعض اوقات انسان کی دبی ہوئی فطرت کو اس کے مدفن سے باہر نکال کر ننگا کر دیتا
ہے اور پھر وہی فطرت کی آواز جو ہزاروں پردوں کے نیچے دبی ہوئی ہونے کی وجہ سے
54
Page 55
سنائی نہ دیتی تھی اب باہر نکل کر ہمارے سامنے آجاتی ہے.اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو اُس کی فطرت کی
آوازیں زیادہ وضاحت کے ساتھ اس کے کانوں میں سنائی دینے لگتی ہیں.اس کی بھی
یہی وجہ ہے کہ جوانی میں عموماً ہزاروں قسم کی غفلتیں انسان
کو گھیرے رکھتی ہیں اور دنیاوی
کاروبار کی بھی کثرت ہوتی ہے اور جذبات بھی جوش کی حالت میں ہونے کی وجہ سے
عمو مأحد اعتدال سے تجاوز کر جاتے ہیں.لیکن جب انسان بوڑھا ہونے لگتا ہے تو یہ
جوش و خروش ٹھنڈا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور یہ غفلتیں دور ہونی شروع ہو جاتی ہیں اور
دنیاوی کاروبار سے بھی قدرے فرصت ملتی ہے تو اس صورت میں فطرت کو پھر موقعہ مل
جاتا ہے کہ اپنی آواز انسان کے کانوں تک پہنچا سکے.دیکھ لودہریوں میں اکثر جوان نظر
آئیں گے اور جب اُن کی جوانی ڈھلنے لگتی ہے تو عموماً اس کے ساتھ ہی اُن کے خیالات
میں ایک تغیر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے.حتیٰ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑھاپے کی حالت
میں پہنچ کر بہت سے دہر یہ خدا کے قائل ہو جاتے ہیں کیونکہ اب اُن کی فطری آواز ان
تک پہنچتی رہتی ہے اور اُن کو مجبور کرتی ہے کہ وہ انکار سے باز آجائیں.مستثنیات کا
سوال الگ ہے ورنہ عام قاعدہ یہی ہے جو اوپر بیان کیا گیا ہے.ہاں اگر کسی شخص کو
بڑھاپے میں بھی ایسے حالات درپیش رہیں کہ جو اس کی فطرت کو دبائے رکھیں تو وہ
بیشک دہریت کی حالت پر ہی قائم رہے گا لیکن چونکہ اس قسم کے غافل کن حالات
زیادہ تر جوانی میں ہی پیش آتے ہیں اس لئے دہریت کا شکار بھی اکثر نوجوان ہی ہوتے
ہیں.کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ تبدیلی فطرت کی آواز کی وجہ سے نہیں بلکہ موت کے ڈر کی
وجہ سے ہوتی ہے.یعنی جب ایک بوڑھا شخص دیکھتا ہے کہ اب میری موت قریب ہے
تو طبعا وہ خائف ہونا شروع ہوتا ہے اور اس خوف کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خدا کی طرف
55
Page 56
مائل ہو جاتا ہے.میں کہتا ہوں کہ یہ دلیل تو ہمارے حق میں ہے نہ کہ ہمارے خلاف.موت کا خوف بھی تو ایک فطری آواز ہے ورنہ ایک دہر یہ کیا اور موت کا خوف کیا؟ جو
شخص اپنی زندگی کو محض اتفاق کا نتیجہ قرار دیتا ہے اس کی نظر میں موت سوائے اس کے
اور کوئی حقیقت نہیں رکھ سکتی کہ وہ زندگی جو اتفاق
کا نتیجہ تھی اب اتفاق کے نتیجہ میں ہی یا
کسی اور وجہ سے اُس کا ہمیشہ کے لئے خاتمہ ہورہا ہے، اور بس.پس موت کا قرب
ایک دہریہ کے دل پر کوئی اثر نہیں ڈال سکتا.لہذا ثابت ہوا کہ خود موت کا خوف بھی کسی
اندرونی تغیر کا نتیجہ ہے اور اسی کا نام ہم فطرت کی آواز رکھتے ہیں.بات وہی ہے کہ
جب غفلت اور ظلمت کے پردے اُٹھنے شروع ہوتے ہیں تو ہماری فطرت پھر ہمارے
دل پر حکومت کرنے کا موقعہ پالیتی ہے اور ہم ایک غیر محسوس طاقت سے ایمان باللہ کی
طرف کھنچنا شروع ہو جاتے ہیں.حضرت مسیح موعود علیہ السلام کیا خوب فرماتے ہیں ؎
آنکھ کے اندھوں کو حائل ہوگئے سو سو حجاب
ورنہ قبلہ تھا تیرا رُخ کافر و دیندار کا
الغرض فطرت انسانی ہستی باری تعالیٰ کا ایک زبر دست ثبوت ہے جس سے کوئی
عقلمند انکار نہیں کر سکتا اور یہ ہم پر اللہ تعالیٰ کا سراسر احسان ہے کہ اُس نے ہماری ہدایت
کے لئے ہماری فطرت کے اندر ہی ایمان کا بیج بو رکھا ہے.چنانچہ قرآن شریف فرما تا
ہے:.وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُوْنَ
یعنی اے لوگو! تمہیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں تمہارے تو خود اپنے نفسوں
میں خُدائی آیات موجود ہیں مگر تم دیکھو بھی.کسی شاعر نے خوب کہا ہے.سورة الذاريات - آیت 22
56
Page 57
دل کے آئینہ میں ہے
یار
ذرا گردن جھکائی دیکھ لی
اس شاعر نے تو نہ معلوم کس خیال سے یہ شعر کہا ہوگا لیکن اس میں شک نہیں کہ
خدا نے اپنی تصویر ہر انسان کے دل میں منقوش کر رکھی ہے مگر متکبر انسان اپنی گردن کو
جھکانے کے لئے تیار نہیں ہوتا.خدا نے ہر انسان کی فطرت کے اندر اپنے عشق کی
چنگاری مرکوز کی ہے مگر کم ہیں جو اس آگ کو بجھنے سے بچاتے ہیں.حضرت مسیح موعود
جس
علیہ السلام فرماتے ہیں.تو نے خود رُوحوں پہ اپنے ہاتھ سے چھڑکا نمک
ہے شور محبت عاشقان زار کا
ایک دم بھی کل نہیں پڑتی مجھے تیرے سوا
جاں گھٹی جاتی ہے جیسے دل گھٹے بیمار کا
شور کیسا ہے تیرے کوچے میں لے جلدی خبر
خوں نہ ہو جائے کسی دیوانہ مجنوں وار کا
کائنات خلق اور نظام عالم کی دلیل
اس کے بعد میں اس دلیل کو لیتا ہوں جو عقلی دلائل میں سے سب سے زیادہ
معروف ہے بلکہ دراصل یہی ایک دلیل ہے جس پر دنیا کے بیشتر حصہ کے ایمان کا
دار و مدار ہے اور ویسے بھی غور کیا جاوے تو درحقیقت جہاں تک انسان کی مجر د عقل کی
پہنچ ہے اس سے زیادہ روشن اور سریع الاثر دلیل خیال میں نہیں آسکتی.یادر ہے کہ
یہاں ان دلائل و براہین کا ذکر نہیں جو آسمان سے نازل ہوتی ہیں اور جن سے خدا تعالیٰ
کا وجود حق الیقین کے طور پر ثابت ہو جاتا ہے اور جن کے ذریعہ سے انسان خدا کی
57
Page 58
طرف محض اشارہ ہی نہیں پاتا بلکہ واقعی خدا کو دیکھ لیتا اور پالیتا ہے.بلکہ یہاں صرف
عقلی دلائل کا ذکر ہے جن کی پہنچ ” ہونا چاہئے“ والے ایمان سے آگے نہیں اور اس قسم
کے دلائل میں واقعی وہ دلیل جو میں اب بیان کرنا چاہتا ہوں ایک نہایت ہی روشن دلیل
ہے اور یہ زیادہ تر اسی دلیل کی برکت ہے کہ باوجود اس کے کہ اس زمانہ میں دنیا
خدا تعالیٰ کے عرفان سے گویا کلیتہ تاریکی میں ہے وہ باری تعالیٰ کے وجود سے بالکل
منکر ہو جانے سے بھی بچی ہوئی ہے اور اسے اس معاملہ میں انکار کی طرف قدم اٹھانے
کی جرات نہیں ہوتی اور یہی وہ ابتدائی دلیل ہے جو ہمیشہ الہی کتب میں بھی غافل
انسانوں کو بیدار کرنے کے لئے استعمال ہوتی رہی ہے اور قرآن شریف نے بھی اسے
کثرت کے ساتھ بار بار استعمال کیا ہے.یہ دلیل مسبب (Effect) سے سبب (Cause) کی طرف جانے کی دلیل
ہے اور اگر علمی طور پر دیکھا جاوے تو یہ دلیل در اصل دو دلیلوں
کا مجموعہ ہے.ایک دلیل تو
وہ عام معروف دلیل ہے جس میں فی الجملہ طور پر مخلوق کے وجود سے خالق کے وجود پر
استدلال کیا جاتا ہے اور یہ دلیل سادہ ہونے کی وجہ سے عامۃ الناس کو زیادہ اپیل کرتی
ہے.دوسری دلیل وہ ہے جس میں اس عالم دنیوی کے حالات اور نظام عالم کا مطالعہ
کر کے اس عالم کی پیدا کرنے والی اور اس نظام کی جاری کرنے اور قائم رکھنے والی ہستی
کے وجود پر دلیل پکڑی جاتی ہے اور یہ دلیل آگے خود کئی حصوں میں منقسم ہو جاتی ہے مگر
اس جگہ اختصار وسہولت کی غرض سے ان دو دلیلوں کو ایک ہی مخلوط دلیل کی صورت میں
بیان کیا جاوے گا.پہلا حصہ دلیل کا جو مخلوق کے وجود سے خالق کے وجود کی طرف جانے سے تعلق
رکھتا ہے اپنی ظاہری صورت میں بہت سادہ ہے.مثلاً میں دیکھتا ہوں کہ اس وقت جب
کہ میں منصوری پہاڑ پر ایک دوست کے گھر میں مہمان کے طور پر ٹھہرا ہوا اس مضمون کا
58
Page 59
یہ حصہ لکھ رہا ہوں میرے سامنے میز پر بہت سی چیز میں رکھی ہیں اور ہر چیز اپنی ہستی سے
مجھے ایک سبق دے رہی ہے.میرے سامنے کاغذ ہے.میرے ہاتھ میں قلم ہے.اس
قلم میں روشنائی ہے.روشنائی کو خشک کرنے کے لئے میرے کاغذ کے نیچے جاذب ہے
اور کاغذوں کو ادھر اُدھر اڑنے سے بچانے کے لئے اُن پر شیشے کا ایک خوبصورت ٹکڑا
رکھا ہے جسے پیپر ویٹ کہتے ہیں.میرے بیٹھنے کے لئے میرے نیچے کرسی ہے اور سہارا
لینے کے لئے میرے سامنے میز ہے.میز کو صاف رکھنے اور خوشنما بنانے کے لئے میز پر
ایک میز پوش ہے اور میز پر ایک طرف کچھ کتابیں رکھی ہیں جنہیں میں بوقت ضرورت
مطالعہ کرتا ہوں.یہ سب چیزیں اس وقت میرے سامنے ہیں اور محض اپنے موجود
ہونے سے میرے اندر یہ یقین پیدا کر رہی ہیں کہ انہیں کسی بنانے والے نے بنایا ہے.پھر میں کسی کمرے کے اندر ہوں اس کمرے کی چاروں طرف دیوار میں ہیں.اُن کے
او پر چھت ہے.کمرے میں کچھ کھڑکیاں اور دروازے ہیں جن پر پردے لٹک رہے
ہیں.کمرے کے فرش پر دری ہے اور دری پر ادھر اُدھر کچھ سامان رکھا ہے.میں اِن
چیزوں کو دیکھ رہا ہوں اور میرا دل اس یقین سے بھرا ہوا ہے کہ یہ چیزیں خود بخود نہیں
بلکہ کسی کاریگر کی محنت کا ثمرہ ہیں.اگر کوئی شخص میرے پاس آئے اور مجھ سے یہ منوانا
چاہے کہ یہ ساری چیزیں جو مجھے نظر آرہی ہیں انہیں کسی نے نہیں بنایا بلکہ یہ خود بخودہی
اپنی موجودہ شکل میں ظاہر ہوگئی ہیں تو میں اس کی بات
کو کبھی نہیں مانوں گا اور نہ کوئی اور
شخص ماننے کو تیار ہو گا.مگر افسوس اس دنیا میں لاکھوں ایسے لوگ ہیں جو ہم سے یہ بات
منوانا چاہتے ہیں کہ یہ زمین، یہ آسمان، یہ حیوانات، یہ نباتات، یہ جمادات، یہ
اجرام سماوی، یہ طبقات ارضی، یہ جسم انسانی کسی صانع کی صنعت کا ثمرہ نہیں بلکہ خود بخود
ہمیشہ سے چلے آئے ہیں.میں ان کی بات کو کس طرح مان لوں ؟ میرے سامنے اس
وقت عرب کے ایک بدوی کا قول ہے جس سے کسی نے پوچھا تھا کہ تیرے پاس خدا کی
59
Page 60
کیا دلیل ہے؟ اُس نے جواب دیا:
الْبَعْرَةُ تَدُلُّ عَلَى الْبَعِيْرِ وَاثَرُ الْقَدَمِ عَلَى السَّفِيْرِ فَالسَّمَاءُ
ذَاتُ الْبُرُوْجِ وَالارْضُ ذَاتُ الْفِجَاجِ أَمَا تَدُلُّ عَلَى قَدِيرِ
یعنی جب کوئی شخص جنگل میں سے گذرتا ہوا ایک اونٹ کی مینگنی دیکھتا ہے تو یہ مجھ
لیتا ہے کہ اس جگہ سے کسی اونٹ کا گذر ہوا ہے اور جب وہ صحرا کی ریت پر کسی آدمی کے
پاؤں کا نشان پاتا ہے تو یقین کر لیتا ہے کہ یہاں سے کوئی مسافر گذرا ہے تو کیا تمہیں یہ
زمین مع اپنے وسیع راستوں اور یہ آسمان مع اپنے سورج اور چاند اور ستاروں کے دیکھ کر
اس طرف خیال نہیں جاتا کہ ان کا بھی کوئی بنانے والا ہوگا ؟
اللہ اللہ ! کیا ہی سچا.کیا ہی تصنع سے خالی مگر دانائی سے پر یہ کلام ہے جو اس
ریگستان کے ناخواندہ فرزند کے منہ سے نکلا، مگر جس کی گہرائی تک یورپ و امریکہ کا
فلسفی با وجود اپنی حکمت و فلسفہ کے نہ پہنچ سکا!
قرآن شریف خلق و نظام عالم کے متعلق فرماتا ہے:.افِي اللهِ شَكٍّ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ.إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمواتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي
تَجْرِي فِى الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ
فَأَحْيَابِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيْفِ الرِّيح
وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُوْنَ.وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ.اَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَهَا وَزَيَّتْهَا وَمَالَهَا مِنْ فُرُوْجٍ
سورة ابراهيم - ايت 11
سورة الذاريت - آیت 22
60
سورة البقره - آيت 165
Page 61
وَالْأَرْضَ مَدَدْنَهَا وَالْقَيْنَا فِيْهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيْجٍ
تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيْبٍ.وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً.وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُوْنَ
وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيْكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ
لَّبَناً خَالِصاً سَآئِعَاً لِلشَّارِبِيْنَ.وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَن تَخِذِي مِنَ
الْجِبَالِ بُيُوتاً وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ.ثُمَّ كُلِيْ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ
فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلا يَخْرُجُ مِنْ بُطُوْنِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيْهِ
شِفَآءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُوْنَ *
ط
فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلى طَعَامِهِ - اَنَّا صَبَيْنَا الْمَاءَ صَبَّاً - ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقا
فَأَنْبَتْنَا فِيْهَا حَبًّا - وَعِنَبَاً وَقَضْباً - وَّزَيْتُوْناً وَنَحْلاً وَحَدَائِقَ غُلْباً - وَفَاكِهَةً
وَّابًا مَّتَاعاً لَّكُمْ وَلَانْعَامِكُمْ.تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ ، وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْيءٍ قَدِيرُ الَّذِي خَلَقَ
الْمَوْتَ وَالْحَيوةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلاً وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُ الَّذِي
خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًاً.سَمَوَاتٍ طِبَاقَاً ماتَرى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَوُتٍ فَارْجِعِ
الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِن فُطُوْرٍ - ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ
حَاسِنَا وَهُوَ حَسِيْرٌ.وَاَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهى.ل سورة ق ـ آيات7تا9 سورة الرعد آیت 16 ٣ سورة يس - آیت 41
سورة النحل: آيات 70,69,67 هـ سورة عبس : آيات 25 تا 33
سورة الملک آیات 2 تا 5
61
سورة النجم.آیت 43
Page 62
قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا اكْفَرَهُ.یعنی کیا تم خدا کی ہستی کے متعلق شک کرتے ہو؟ وہ خدا جو زمین و آسمان کو نیست
سے ہست میں لانے والا ہے.یقیناً آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے بدلنے میں اور اُن
جہازوں میں جولوگوں کے نفع کی چیزیں اُٹھائے ہوئے سمندر کے اندر چلتے پھرتے ہیں
اور اُس پانی میں جو خدا اوپر سے اُتارتا ہے اور جس کے ذریعہ سے وہ مردہ زمین کو زندہ
کرتا اور جاندار چیزوں کو زمین میں پھیلاتا ہے اور ہواؤں کے چلنے میں اور اُن بادلوں
میں جو آسمان اور زمین کے درمیان
مسحر ہیں خدا کی طرف سے نشان ہیں اُن لوگوں کے
لئے جو سوچتے ہیں.اور خود تمہارے اپنے نفسوں میں بھی خدائی نشان موجود ہیں مگر تم دیکھو بھی.کیا لوگ اس آسمان کی طرف آنکھ اُٹھا کر نہیں دیکھتے جو ان کے سروں کے اُوپر
ہے ہم نے اُسے کس طرح بنایا ہے اور پھر کس طرح اُسے مختلف اجرام سے مزین کیا
ہے اور اُس میں کوئی رخنہ نہیں ہے اور پھر ہم نے کس طرح زمین کو ( باوجود اُس کے گول
ہونے کے ) پھیلا رکھا ہے اور اُس میں پہاڑ کھڑے کئے ہیں اور اس میں ہر قسم کی
بارونق چیزوں کے جوڑے پیدا کئے ہیں.یہ نظارہ اس لئے ہے کہ تا غور کرنے والے
بندوں کی آنکھیں کھلیں اور وہ اپنے بھولے ہوئے خدا کو پھر یا د میں لے آئیں.اور پھر یہ بھی دیکھو کہ ہر چیز خواہ وہ آسمان میں ہے یا زمین میں ہے اللہ تعالیٰ کے
سامنے اطاعت کا سجدہ بجالا رہی ہے اور اس قانون سے باہر نہیں جاسکتی جو خدا نے اس
کے لئے مقرر کر رکھا ہے.اور ہر چیز اپنے اپنے دائرہ میں الگ الگ چل رہی ہے اور دوسری چیزوں سے
ل سورة عبس: آیت 18
62
Page 63
ٹکراتی نہیں.اور پھر دودھ دینے والے چوپائیوں پر نگاہ ڈالو کیونکہ اُن میں بھی تمہارے لئے
ایک سبق ہے.دیکھو ہم کس طرح ان کے پیٹوں کے گوبر اور خون میں سے خالص دودھ
تمہارے لئے الگ کر دیتے ہیں جو پینے والوں کے لئے لذت اور فائدہ کا موجب ہوتا
ہے اور ہاں ذرا شہد کی مکھی کی طرف بھی دیکھنا.تمہارے رب نے اُسے یہ حکم دے رکھا
ہے کہ وہ پہاڑوں اور درختوں اور بیل دار پودوں کے اوپر اپنے مکان بنائے اور پھر
پھلوں کا رس چوسے.اور مطیع ہو کر تمہارے رب کے راستوں پر چلے تا کہ اُس کے پیٹ
سے مختلف رنگوں کا شہر برآمد ہو جس میں لوگوں کے لئے شفا رکھی گئی ہے.یقیناً غور
کرنے والوں کے لئے اس میں بھی ایک نشان ہے.پھر اے انسان! اپنے روزمرہ کے کھانے کی طرف نگاہ کر اور دیکھ کہ ہم کس طرح
تیری خاطر ایک قاعدہ کے ماتحت پانی کو اوپر سے گراتے ہیں اور پھر ایک ضابطہ سے
سطح زمین کو پھاڑتے ہیں اور پھر اُس میں سے غلہ اگاتے ہیں اور انگور اور سبزی اور
زیتون اور کھجور میں اور میووں سے لدے ہوئے باغات اور پھل اور چارہ پیدا کرتے
ہیں تاوہ تمہارے لئے اور تمہارے مویشیوں کے لئے سامانِ زندگی کا کام دے.پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں یہ ساری حکومت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر
ہے.اور وہ وہی تو ہے جس نے تمہارے لئے موت وحیات کا سلسلہ جاری کیا تا وہ یہ
دیکھے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال بجالاتا ہے اور کون نہیں.اور وہ غالب اور بخشنے والا
خُدا ہے جس نے تمہارے سروں پر سات بلندیوں کو ترتیب کے ساتھ پیدا کیا.اے
انسان! کیا تو رحمن کی مخلوق میں کوئی نقص پاتا ہے؟ اپنی نظر کو چاروں طرف دوڑا اور پھر
بتا کہ کیا تجھے کوئی فتور نظر آتا ہے؟ اور پھر دوبارہ سہ بارہ نظر کو چکر دے مگر یا درکھ کہ تیری
نظر تیری طرف ہر دفعہ ذلیل وماندہ ہو کر لوٹے گی اور خدا کی خلق میں کوئی رخنہ نہ
63
Page 64
دریافت کر سکے گی.کیا یہ ساری باتیں تجھے خدا کی طرف راستہ نہیں دکھاتیں؟
ہلاک ہو گیا انسان ! وہ کیسا ناشکر گذار ہے.یہ آیات قرآنی جو قرآن شریف کے مختلف حصوں سے لی گئی ہیں جس فصاحت
و بلاغت کے ساتھ کائنات خلق اور نظامِ عالم کی طرف توجہ دلا کر ہستی باری تعالیٰ کا
نشان دے رہی ہیں وہ محتاج تفسیر نہیں.واقعی ایک غور کرنے والی طبیعت کے لئے دُنیا
کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ کر ہی ہے اور انسان جس قدر بھی نظام عالم اور
خواص اشیاء کے مطالعہ میں ترقی کرتا ہے اس کے لئے یہ اشارہ زیادہ واضح اور زیادہ
معتین صورت اختیار کرتا جاتا ہے.دُنیا کی ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز کو لے لو اور پھر اس
پر غور کرو.تم دیکھو گے کہ وہ حقیر چیز ایک ایسے عظیم الشان اور حکیمانہ قانون کے ماتحت
کام کر رہی ہے اور اس میں ایک ایسی ترتیب اور علت غائی نظر آتی ہے کہ عقل حیران
ہو جاتی ہے اور اس کا چھوٹے سے چھوٹا حصہ بھی انسانی دماغ کے لئے لا نخل عقدہ پیش
کرتا ہے.حضرت مسیح موعود بانی سلسلہ احمدیہ فرماتے ہیں.بنا سکتا نہیں اک پاؤں کیڑے کا بشر ہرگز
تو پھر کیونکر بنانا نور حق کا اس پہ آساں ہے
ایک مکھی کو ہی دیکھو.یہ حقیر جانور بھی کس درجہ تک خدا کی عظیم الشان قدرت
نمائیوں کا کرشمہ ہے.اگر انسان ساری عمر صرف ایک مکھی اور اُس کے اعضاء وغیرہ
کے متعلق تحقیق کرنے میں صرف کر دے تو یقیناً وہ دیکھے گا کہ اس کی زندگی تو ختم
ہو جاو گی لیکن تحقیق کا میدان ابھی اس کی آنکھوں کے سامنے غیر دریافت شدہ حالت
میں پڑا ہوا نظر آئے گا.خود انسانی جسم کو دیکھ لو.جب سے یہ دنیا بنی ہے دنیا کے بہترین
دماغ ہر زمانہ میں لاکھوں کی تعداد میں اس کی بناوٹ کے متعلق تحقیق کرتے چلے آئے
64
Page 65
ہیں اور اس حکیمانہ قانون کے معلوم کرنے کے پیچھے پڑے رہے ہیں جو مختلف اعضاء
انسانی یعنی دل و دماغ ، گردہ، پھیپھڑا، جگر ، معدہ، آنکھ ، کان ، ناک وغیرہ میں کام کر رہا
ہے لیکن خدا کی اس بظاہر چھوٹی سی کان کا کتنا حصہ ہے جو وہ اس وقت تک دنیا کے
سامنے نکال کر پیش کر سکے ہیں؟ اور یقینا دنیا کا خاتمہ آ جائے گا لیکن اس عالم صغیر کے
خزانے ختم نہ ہونگے.ایک پھول کو ہی لے لو جو تمہارے راستہ کے ایک کنارے پر خودروطور پر نکل آتا
ہے اور بسا اوقات کسی بے درد غافل را بگیر کے پاؤں کے نیچے مسلا جا کر ہمیشہ کے لئے
دنیا کی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے.اس کی شخصی مشخصی پتیوں میں سینکڑوں رگیں اور
نالیاں ایک جال کی طرح پھیلی ہوئی ہوتی ہیں اور یہ ہر رگ اور ہر نالی اپنے کام اور اپنے
قانون کے لحاظ سے ایک عالم کا حکم رکھتی ہے جس کی کامل دریافت کے واسطے عمر نوح
بھی کافی نہیں ہو سکتی.ہاں ذرا اس حقیر اور قریبا نہ نظر آنے والے تم پر بھی ایک نظر ڈالو
جو ایک مٹھی بھر جگہ میں لاکھوں کی تعداد میں سا سکتا ہے لیکن جب وہ زمین میں ڈالا جاتا
ہے تو دیکھتے ہی دیکھتے ایک عظیم الشان درخت بن جاتا ہے جس کے سایہ کے نیچے
ہزاروں انسان آرام کر سکتے ہیں.اور کیا تم نے انسانی زندگی کا بھی مطالعہ کیا ہے؟ ایک
وقت تھا کہ انسان ایک ایسے حقیر خوردبینی کیڑے کی شکل میں اپنے باپ کے جسم کا حصہ
تھا کہ شاید کوئی نازک مزاج شخص اُسے دیکھنا بھی گوارا نہ کرتا، لیکن آج وہی ہے کہ ایک
خوبصورت، دلکش اور دل و دماغ کی اعلیٰ ترین طاقتوں سے آراستہ وجود بنا بیٹھا ہے.آؤ اب ذرا آسمان کی طرف بھی ایک نظر اُٹھا کر دیکھو.یہ سورج، یہ چاند، یہ
ستارے تمہارے سامنے کیا منظر پیش کرتے ہیں.سورج ہی کو لے لو.کیا تمہیں معلوم
ہے کہ یہ سورج تمہاری زمین سے کتنے فاصلہ پر ہے؟ سنو ! اس کا فاصلہ زمین سے نو کروڑ
تمیں لاکھ میل ہے اور اگر حیران نہ ہو تو میں تمہیں بتاؤں کہ اجرام سماوی میں سے تمہارا
65
Page 66
یہ سُورج اُن ستاروں میں سے ہے جو نسبتاً زمین کے زیادہ قریب ہیں کیونکہ بعض
ستاروں کا زمین سے اتنا فاصلہ ہے کہ اُس کے اظہار کے لئے تمہاری زبان میں کوئی عدد
تک مقرر نہیں پھر یہ بھی جانتے ہو کہ سورج کا حجم کتنا ہے؟ یہ بھی سُن لو.تمہاری یہ زمین
جس کی وسعت پر تمہیں اتنا ناز ہے اور جو باوجود گول ہونے کے اپنی عظیم الشان وسعت
کی وجہ سے چپٹی نظر آتی ہے سات ہزار نو سو چھیں میل کا قطر رکھتی ہے.مگر اس کے
مقابلہ میں سورج کا قطر آٹھ لاکھ پینسٹھ ہزار میل ہے لیکن اگر حیران نہ ہو تو میں پھر تم سے
یہ بھی کہہ دوں کہ آسمانی ستاروں میں سے بہت سے ستارے ایسے ہیں جن کے سامنے
یہ سورج حجم کے لحاظ سے اتنی بھی حیثیت نہیں رکھتا جیسے کہ ایک عقاب کے مقابلہ میں
پدی کی حیثیت ہے.یہ تو ان فضا نشینوں کی ظاہری شکل وصورت کا حال ہے اور اگر اس عظیم الشان
نظام کا مطالعہ کیا جائے جس کے ماتحت یہ لاکھوں کروڑوں عالم فضاء آسمانی میں چکر
لگارہے ہیں تو عقل انسانی خود چکر میں آنے لگتی ہے اور پھر کمال یہ ہے کہ ہر ستارہ اپنے
اپنے دائرہ کے اندر اپنے اپنے قواعد کے ماتحت چگر لگا رہا ہے اور کیا مجال ہے کہ ایک
ستارہ کسی دوسرے ستارے سے ٹکرا جاوے یا اپنے دائرہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے دائرہ
کے اندر جا داخل ہو اور یہ قاعدہ صرف اجرام سماوی ہی کے متعلق نہیں بلکہ زمین پر بھی ہر
چیز اپنے اپنے حلقہ کے اندر محصور ہے اور یہ کسی کو طاقت نہیں کہ اپنے حلقہ سے آزاد ہو کر
دوسرے حلقے میں داخل ہو سکے.آگ کا کام ہے کہ جلاوے.پانی کا کام ہے کہ
بجھاوے.درخت کا کام ہے کہ زمین میں ایک جگہ استادہ کھڑا رہے.پرندہ کا کام ہے
کہ ہوا میں اُڑتا پھرے.انسان کا کام ہے کہ زمین پر چلے.مچھلی کا کام ہے کہ پانی میں
تیرے.گائے کا کام ہے کہ گھاس کھائے.شیر کا کام ہے کہ دوسرے جانوروں کو اپنی
خوراک بنائے.یہ موٹی موٹی مثالیں ہیں ورنہ ہر چیز اپنے خواص اور اپنی طاقتوں اور
66
Page 67
اپنے کام کے لحاظ سے اپنے اپنے حلقہ کے اندر محصور ہے اور اپنے حلقہ سے باہر نکل
جانے کی کسی کو طاقت نہیں اور پھر ہر چیز ایک خاص غرض و مقصد کو پورا کر رہی ہے.آب غور کرو اور سوچو کہ کیا یہ عظیم الشان نظام جس سے زمین و آسمان کی کوئی چیز
باہر نہیں خود بخود اپنے آپ سے ہے؟ کیا یہ حکیمانہ قانون جو ہر چیز میں کام کرتا نظر آرہا
ہے خود بخود بغیر کسی بالا ہستی کے تصرف کے جاری ہے؟ کیا یہ زمین مع اپنی لا تعداد
مخلوقات کے اور یہ آسمان مع اپنے بے شمار اجرام کے اپنے خالق اور اپنے رب آپ ہی
ہیں؟ اس وقت اس سوال
کو چھوڑو کہ اگر کوئی خدا ہے تو وہ کون ہے اور کہاں ہے؟ صرف
اس بات کا جواب دو کہ کیا تمہارا دل اس بات پر اطمینان پاتا ہے کہ یہ کائنات اور یہ
نظام بغیر کسی خالق ، بغیر کسی رب، بغیر کسی مالک، بغیر کسی متصرف کے، خود بخود اپنے آپ
سے ہے؟ میں یہ نہیں پوچھتا کہ تم کسی خدا پر ایمان لاتے ہو یا نہیں بلکہ میرا سوال صرف
یہ ہے کہ کیا تم دیانتداری کے ساتھ کہہ سکتے ہو کہ یہ زمین یہ آسمان یہ حیوانات یہ نباتات
یہ جمادات یہ اجرام سماوی یہ طبقات ارضی محض اتفاق کا نتیجہ ہیں؟ کیا یہ عظیم الشان نظام
جس نے دنیا کی اربوں چیزوں کو ایک لڑی میں پرورکھا ہے بغیر کسی خالق اور متصرف
کے خود بخود چل رہا ہے؟ میں نہیں سمجھ سکتا کہ کوئی شخص جو آدم کی اولاد سے ہے اور
دل ودماغ رکھتا ہے اس بات پر تسلی پاسکتا ہے کہ یہ کائنات جو اس قد رگونا گوں عجائبات
کا مجموعہ ہے خود بخود اپنے آپ سے ہے.خلاصہ کلام یہ کہ یہ تمام کائنات مع اپنے
حکیمانہ نظام کے خدا تعالیٰ کی ہستی کی ایک ایسی زبر دست دلیل ہے کہ کوئی عقلمند شخص اس
سے انکار نہیں کر سکتا.اس وقت تک میں نے دنیا کی مختلف چیزوں اور اُن کے حصوں کو انفرادی
صورت میں لیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ دنیا کی ہر چیز اپنی ذات میں ایسی عجیب و غریب ہستی
ہے اور ایسے حکیمانہ قانون کے ماتحت چل رہی ہے کہ انسان مجبور ہوتا ہے کہ دُنیا کی
67
Page 68
پیدائش کو ایک علیم اور قد مر اور حکیم اور متصرف ہستی کی طرف منسوب کرے لیکن جب ہم
کسی ایک چیز کے مختلف حصوں کے آپس کے تعلقات پر نظر ڈالتے ہیں یا مختلف چیزوں
کے باہمی تعلقات کا مطالعہ کرتے ہیں تو پھر یہ دلیل اور بھی زیادہ روشن ہوکر ہمارے
سامنے ظاہر ہوتی ہے.مثلاً ہم اونٹ کو لیتے ہیں اور بالفرض پر مان لیتے ہیں کہ
قانون قدرت کے کسی مخفی اور غیر معلوم قاعدہ کے ماتحت اس کو لمبی ٹانگیں مل گئیں.یعنی
اونٹ کی لمبی ٹانگوں کا ملنا نیچر کے کسی قانون کا نتیجہ ہے.مگر سوال یہ ہے کہ اس اندھے
قانون کو یہ کیسے پتہ لگ گیا کہ اب جو میں نے اسے لمبی ٹانگیں دی ہیں تو اس کی گردن
بھی لمبی بنانی چاہئے تا کہ اس کا منہ آسانی کے ساتھ زمین تک پہنچ سکے.اور پھر صرف
اونٹ میں ہی نہیں بلکہ ہر جانور میں یہی حکیمانہ قاعدہ جاری کر دیا کہ جہاں کسی مصلحت
سے
ٹانگیں لمبی دی جائیں وہاں گردن بھی لمبی ہو اور جہاں ٹانگیں چھوٹی ہوں وہاں
گردن بھی چھوٹی ہو.کہا جاسکتا ہے کہ یہ لمبے عرصہ کے حالات کا طبعی نتیجہ ہے کہ لبی
ٹانگوں کی وجہ سے گردن بھی آہستہ آہستہ لمبی ہو جاتی ہے مگر یہ اعتراض درست نہیں
کیونکہ دنیا میں حیات حیوانی کی تاریخ اس بات کا کوئی ثبوت پیش نہیں کرتی کہ لمبی
ٹانگوں والے جانوروں کی گردنیں پہلے چھوٹی ہوا کرتی تھیں اور پھر بعد میں آہستہ آہستہ
لمبی ہو گئیں.اور پھر اس بات کا بھی کیا جواب ہے کہ لمبی ٹانگوں والے جانور شروع میں
جبکہ اُن کی گردنیں چھوٹی ہوتی تھیں کس طرح گزارہ کرتے تھے؟ بہر حال یہ صرف ایک
موٹی مثال ہے ورنہ غور کیا جائے تو دُنیا میں ہر چیز کے مختلف حصے اس تناسب اور
موزونیت کے ساتھ باہم جوڑے گئے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے.پھر ذرا آگے چلیں تو اس سے بھی بڑھ کر عجیب و غریب اور دلکش منظر نظر آتا ہے.قانونِ قدرت کے کسی اتفاقی کرشمہ نے مرد کی پشت میں نسلِ انسانی کے کیڑے پیدا کر
دیئے.اور پھر اس قانون نے ہی مرد اور عورت کے اندر یہ خواہش پیدا کر دی کہ وہ ایک
68
Page 69
جگہ جمع ہوں اور اُسی نے ہی مرد کی پشت کے وہ کیڑے عورت کے تاریک و تار رحم میں
پہنچا دیئے اور پھر اسی قانون نے ہی نو ماہ تک اُن میں سے ایک کیڑے کو منتخب کر کے اس
کی تربیت کی اور اُسے ایک دل و دماغ رکھنے والا خوبصورت شکل کا بچہ بنا دیا اور پھر اُسی
نے ہی اُس بچے کو ماں کے پیٹ سے باہر نکالا.گویا کہ اُس کیڑے کے اندرونی
تغیرات سب اسی اتفاقی قانونِ قدرت کے ماتحت وقوع میں آگئے.مگر خدارا مجھے یہ
سمجھا دو کہ اس اندھے قانون کو کہاں سے سوجھی کہ جب وہ بچہ ماں کے رحم سے باہر
آنیوالا ہوا تو اُس نے اُس کی خوراک کے واسطے ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر دیا تا
پیشتر اس کے کہ بچہ اس دنیا کی روشنی دیکھے اُس کی خوراک پہلے سے دنیا میں موجود ہو.ماں کی چھاتیاں تو بچے کے جسم کا حصہ نہیں پھر یہ کیسے ہوا کہ بچے کی خاطر دوسری جگہ ماں
کی چھاتیاں اُبھرنی شروع ہو گئیں.سبحان اللهِ ، مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ
پھر اور سنو.زمین خود بخود پیدا ہوگئی.اُس پر چلنے پھرنے والی چیزیں بھی
خود بخود پیدا ہوگئیں.انسان بھی اپنے آپ نیست سے ہست میں آ گیا.اُس کے ناک
کان آنکھ سب خود بخود ظاہر ہو گئے.الغرض یہ سب کچھ کسی اتفاقی قانون کے نتیجے میں
ہو گیا، لیکن یہ کس طرح ہوا کہ آنکھوں میں جو دیکھنے کی طاقت تھی اُس کے ظاہر کرنے
کے لئے اس قانون نے نو کروڑ میل کے فاصلہ پر ایک عظیم الشان چراغ بھی روشن کر دیا
تا کہ اس کی روشنی زمین پر پہنچے اور پھر انسانی آنکھ اپنی قوت بینائی کو استعمال کر سکے.درخت تو زمین پر اگ آیا.اس کے تخم بھی پیدا ہو گئے اور ختم زمین پر گرا کر بوئے بھی
گئے لیکن یہ کس نے سوچا کہ ان تخموں کے اُگنے کے واسطے پانی کی بھی ضرورت ہے.اور
پھر یہ کس نے انتظام کیا کہ سمندر پر سورج کی شعاعیں گرائیں اور وہاں سے کروڑوں ٹن
پانی اُٹھا کر ہواؤں کے ذریعہ زمین کے جھلتے ہوئے میدانوں تک پہنچا دیا اور پھر وہاں
ا سورة الحج - آیت 75
69
Page 70
ان ہواؤں کو بادل کی صورت میں لا کر بارشیں برسادیں.اگر یہ سب کچھ اسی اتفاقی
قانون نے کیا اور یہی قانون وہ ہستی ہے جو خالق ہے، مالک ہے، رب ہے، علیم ہے،
قدیر ہے، حکیم ہے، متصرف ہے، ہیمن ہے جو غور کرتی اور سوچتی ہے، جو حالات کی
مناسبت کا خیال رکھتی ہے، جو اگر ضرورت پیدا کرتی ہے تو دوسری جگہ اس کے پورا
کرنے کا سامان بھی مہیا کر دیتی ہے تو ہمیں ناموں سے کچھ سروکار نہیں.پھر وہی ہمارا
خدا ہے اور اسی کے سامنے ہم محبت و عبودیت کا سجدہ بجالاتے ہیں.غرض کسی طریق کو
بھی اختیار کیا جاوے اس بات کے ماننے کے بغیر چارہ نہیں کہ یہ کائنات اور اس کا
حکیمانہ نظام ایک ایسی ہستی کی طرف اشارہ کر رہا ہے جو خالق ہے، مالک ہے، حکیم ہے،
علیم ہے، قدیر ہے، متصرف ہے ، غرض ان تمام صفات سے متصف ہے جو مذہب خدا
کی طرف منسوب کرتا ہے.اس جگہ یہ یاد رکھنا چاہئے کہ ہم نے علمی اصطلاحات اور پیچید گیوں سے بچنے
کے لئے محض سادہ طور پر اس دلیل کو بیان کیا ہے تا کہ ہمارے نو جوان عزیز اسے آسانی
کے ساتھ سمجھ سکیں.لیکن اس دلیل کو علمی طور پر بھی بیان کیا جاسکتا ہے جو مختصراً یہ ہے کہ
نیچر کے مطالعہ سے پتہ لگتا ہے کہ اس دُنیا کی لاتعداد مختلف اشیاء میں انفرادی طور پر بھی
اور مجموعی طور پر بھی تین چیزیں پائی جاتی ہیں.اوّل دُنیا کی ہر چیز میں کیا بلحاظ اس کی
اپنی ذات کے اور کیا بلحاظ دوسری چیزوں کے ساتھ اس کے تعلقات کے ایک نہایت
یہ مفصل اور کامل و مکمل قانون جاری ہے جسے انگریزی میں لاء آف نیچر
(Law of Nature) کہتے ہیں اور یہ قانون اگر اس کو صحیح طور پر مطالعہ کیا جاوے تو
صانع عالم کے وجود پر ایک نہایت زبر دست اور روشن دلیل ہے.مگر افسوس ہے کہ بعض
لوگوں نے اپنی کوتاہ نظری سے خود اسی قانون کو اپنے لئے ٹھوکر کا موجب بنارکھا ہے.دوسرے دنیا کی ہر چیز میں اور نیز اس حکیمانہ قانون میں جو نیچر میں کام کر رہا ہے
70
Page 71
نہ صرف انفرادی طور پر بلکہ مجموعی طور پر بھی ایک خاص معین نقشہ اور ترتیب نظر آتی ہے
جسے دیکھتے ہوئے کوئی دانا شخص اسے ہرگز اتفاق کی طرف منسوب نہیں کر سکتا.اس نقشہ
اور ترتیب کو انگریزی میں ڈیزائن (Design) یا پلین (Plan) کہتے ہیں.تیسرے
دُنیا کی ہر چیز معہ اپنے قانون اور معہ اپنے ڈیزائن یا پلین کے ایک خاص غرض و غایت
کے ماتحت کام کرتی ہوئی نظر آتی ہے.یعنی اس عالم دنیوی کی ہر چیز میں ایک
علت غائی ثابت ہوتی ہے اور اس علم کو انگریزی میں ٹیلی آلو جی (Teleology) کہتے
ہیں اور یہ علت غائی ذات باری تعالیٰ کے وجود پر ایک نہایت زبردست دلیل ہے.مختصر یہ کہ نظام عالم کا مطالعہ بڑے زور کے ساتھ انسان کو اس طرف مائل کرتا ہے کہ یہ
دنیا خود بخود اپنے آپ سے نہیں ہے بلکہ ایک مدرک بالا رادہ ہستی کے دست قدرت
سے عالم وجود میں آئی ہے.وھوالمراد.مغربی محققین اور خُدا کا عقیدہ
اس بحث کے ختم کرنے سے قبل میں مغربی محققین کے متعلق بھی کچھ کہنا چاہتا
ہوں جو ہر بات کو سائنس و فلسفہ کی روشنی میں مطالعہ کرنے کے عادی ہیں.سو جاننا
چاہئے کہ اہلِ مغرب میں سے جو لوگ اس زمانہ میں ہستی باری تعالیٰ کے منکر ہوئے ہیں
وہ عموماً سائنس اور فلسفہ جدید کے نظریات سے استدلال کرتے ہیں.ان لوگوں کا یہ
بیان ہے کہ مادہ کے اندر مختلف صورتیں اختیار کر سکنے کا جو ہر طبعی طور پر پایا جاتا ہے اور
مادہ میں یہ بھی ایک فطری خاصہ ہے کہ وہ ایک وقت تک ادنیٰ حالت سے اعلیٰ حالت کی
طرف ترقی کرتا جاتا ہے.چنانچہ وہ یہ دعوی کرتے ہیں کہ یہ مادی دنیا اپنی موجودہ
صورت میں
کئی تبدیلیوں کے نتیجہ میں جو اصولِ ارتقاء کے ماتحت عمل میں آئی ہیں قائم
ہوئی ہے.مثلاً وہ کہتے ہیں کہ انسان ہمیشہ سے اسی شکل و ہیئت میں نہ تھا.بلکہ کسی دُور
71
Page 72
کے گذشتہ زمانہ میں وہ ایک نہایت ہی ادنی قسم کی چیز تھا جس نے آہستہ آہستہ ارتقاء
کر کے اپنی موجودہ شکل وصورت اختیار کی ہے.اسی طرح دُنیا کی دوسری چیزوں کا
حال ہے کہ وہ اپنی ابتدائی حالت میں بالکل ادنی اور سادہ تھیں مگر بعد میں قانون ارتقاء
کے ماتحت آہستہ آہستہ ترقی کر گئیں.اسی طرح اُن کا یہ دعویٰ ہے کہ دنیا کی اکثر چیزیں
جو اس وقت مختلف جنسوں اور مختلف صورتوں اور مختلف خواص میں نظر آتی ہیں کسی زمانہ
میں ان میں اتنا اختلاف نہ تھا بلکہ دنیا اپنی ابتدائی حالت میں صرف چند محدود سادہ
چیزوں کی صورت میں تھی جن سے آہستہ آہستہ ارتقاء کر کے یہ عجائب خانہ عالم پیدا ہوتا
گیا.پس ان لوگوں کا کہنا ہے کہ موجودہ کا ئنات اور اس کے باریک اور مفصل اور
حکیمانہ نظام کو کسی بیرونی صانع کی دلیل میں پیش نہیں کیا جاسکتا.کیونکہ یہ سب کچھ
قانونِ ارتقاء کے ماتحت طبعی طور پر ظہور پذیر ہوا ہے.دوسری بات مغربی محققین یہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا ہمیشہ سے ایک خاص معین قانون
کے ماتحت کام کرتی چلی آئی ہے اور اب بھی دُنیا کی ہر اک چیز ایک خاص قانون کے
ماتحت چل رہی ہے اور ہم علمی تحقیق کے ذریعہ سے ہر تغیر اور ہر حرکت اور ہر سکون کی وجہ
دریافت کر سکتے ہیں.اور ان کا یہ دعوی ہے کہ ہم روز بروز قانونِ نیچر اور خواص الاشیاء
اور تعلقات مابین الاشیاء کی حقیقت تک پہنچتے جاتے ہیں اور سائنس کے مختلف شعبوں
مثلاً فزکس اور کیمسٹری اور میکینکس اور انتھروپالوجی اور جی آلو جی اور بائونی اور زوالوجی
اور اناٹومی اور فزی آلوجی اور اسٹرانومی اور سائی کالوجی وغیرہ وغیرہ میں اس قدر ترقی
ہو چکی اور ہوتی جاتی ہے کہ بے شمار حقائق جو اس سے قبل ایک راز سر بستہ تھے بلکہ ہماری
نظر سے بالکل ہی اوجھل تھے اب ایک منکشف شدہ حقیقت کے طور پر ہمارے سامنے
آگئے ہیں اور سینکڑوں غلط خیالات جو لاعلمی اور جہالت اور سلف کی بے جا اتباع کے
نتیجہ میں ہمارے اندر قائم تھے اب نئے علوم کی روشنی میں دُور ہوتے جاتے ہیں اور
72
Page 73
مسئلہ حیات اور فلسفہ بقاء عالم کی اصل حقیقت دن بدن منکشف ہوتی جاتی ہے.گویا
جن باتوں کو انسان پہلے زمانوں میں اپنی عقل و فہم سے بالا سمجھ کر کسی بالا ہستی کی طرف
منسوب کر دیتا تھا اب ہم انہی باتوں کو نئے علوم کی روشنی میں کسی معتین قانون نیچر کا نتیجہ
ثابت کر سکتے ہیں.لہذا اس کا رخانہ عالم کوکسی خدا و غیرہ کی طرف منسوب کرنا جسے نہ کسی
نے دیکھا اور نہ محسوس کیا ایک جہالت کا خیال ہے.یہ وہ اعتراض ہے جو بعض مغرب کے محققین کی طرف سے ہستی باری تعالیٰ کے
خلاف پیش کیا جاتا ہے، لیکن اگر نظر غور سے دیکھا جائے تو یہ اعتراض ایک بالکل بودا
اعتراض ہے.مسئلہ ارتقاء جس کی تفصیلات میں ہمیں اس جگہ جانے کی ضرورت نہیں اور
قطع نظر اس کے کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے یا کس حد تک صحیح ہے اور کس حد تک غلط ہے
ذات باری تعالیٰ کے خلاف ہرگز بطور دلیل کے پیش نہیں ہوسکتا.کیونکہ یہ مسئلہ کا ئنات
کے حقیقی آغاز کے متعلق کوئی روشنی نہیں ڈالتا بلکہ اس کا تعلق صرف اس بات سے ہے کہ
دنیا کی موجودہ چیزیں ہمیشہ سے اسی طرح نہیں بلکہ ایک ادنیٰ حالت سے ترقی کر کے
اپنی موجودہ حالت کو پہنچی ہیں.لیکن سوال یہ ہے کہ وہ ابتدائی ادنیٰ حالت کی چیزیں
کہاں سے آئیں؟ اس کے متعلق حامیان مسئلہ ارتقاء علمی طور پر کوئی یقینی روشنی نہیں
ڈالتے اور ظاہر ہے کہ جب تک اس دُنیا کی ابتدائی پیدائش کے متعلق کوئی روشنی نہ ڈالی
جائے محض مسئلہ ارتقاء کو خدا کے انکار کے ثبوت میں پیش کرنا قطعاً کوئی اثر نہیں رکھتا.کیا
صرف اس بات کے ثابت ہو جانے سے کہ انسان یا اس دُنیا کی دوسری چیزیں ابتدائی
زمانہ میں کسی ادنیٰ قسم کی حالت میں تھیں اور پھر آہستہ آہستہ ترقی کرتی کرتی موجودہ
حالت کو پہنچیں ، یہ استدلال جائز ہو سکتا ہے کہ اس دُنیا کا پیدا کرنے والا کوئی نہیں ہے؟
ہرگز نہیں.اور اگر یہ کہا جائے کہ جب یہ ثابت ہو گیا کہ یہ دنیا اپنی ابتدائی صورت میں بہت
73
Page 74
سادہ تھی اور پھر مادہ کے اندرونی خواص کے ماتحت وہ زیادہ اعلیٰ اور مکمل صورت اختیار
کرتی گئی تو کم از کم اس سے یہ دلیل تو باطل ہوگئی جو اوپر دی گئی ہے کہ چونکہ موجودہ
کائنات جو بیشمار مختلف چیزوں کا مجموعہ ہے ایک نہایت لطیف اور حکیمانہ قانون کے
ماتحت کام کر رہی ہے.اس لئے معلوم ہوا کہ وہ کسی بیرونی صانع اور علیم ومتصرف ہستی
کے ماتحت ہے تو یہ بھی ایک جہالت کی بات ہوگی کیونکہ ان ابتدائی ادبی حالت کی
چیزوں کے اندر ان خواص کا پایا جانا کہ وہ ترقی کر کر کے ایک عجیب و غریب کائنات کی
صورت اختیار کر لیں اور اس ترقی کے ساتھ ساتھ ہی ایک نہایت ہی پر حکمت قانون بھی
ان کے متعلق پیدا ہوتا چلا جائے خود سب عجوبوں سے بڑھ کر عجوبہ ہے.بلکہ اگر نظر غور
سے دیکھا جائے تو اس مادی دنیا کی وہ ابتدائی حالت جو بیان کی جاتی ہے ( قطع نظر اس
کے کہ وہ درست ہے یا نہیں) موجودہ کا ئنات سے بھی زیادہ عجیب و غریب اور انسانی
عقل کو دنگ کرنے والی ہے.کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ ابتدائی حالت موجودہ دُنیا کے لئے
بطور تخم کے تھی اور ہر عقلمند سمجھ سکتا ہے کہ تم درخت کی نسبت زیادہ عجیب و غریب اور زیادہ
پر حکمت چیز ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر باوجود اس کے کہ وہ حجم میں نہایت چھوٹا اور
صورت میں نہایت سادہ ہوتا ہے وہ تمام طاقتیں اور تمام خواص اور تمام کمالات بالقوة
طور پر مخفی ہوتے ہیں جو بعد میں درخت کے اندر بالفعل رونما ہوتے ہیں.پس اس دُنیا
کا اپنی ابتدائی حالت میں بہت ادنی اور سادہ ہونا اس کا ئنات کو اور بھی زیادہ پُر حکمت
اور عجیب و غریب چیز ثابت کرتا ہے اور خالق فطرت کی ہستی پر ایک مزید دلیل پیدا ہوتی
ہے کہ کس طرح اس نے مادہ کی اس ابتدائی ادنیٰ حالت میں یہ مخفی طاقتیں ودیعت
کر دیں کہ وہ آہستہ آہستہ ایک نہایت عظیم الشان اور پر رعب و پر حکمت عالم کی صورت
اختیار کر گیا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہی کس طرح اس کے اندر سے وہ کمل اور حکیمانہ
قانون بھی پیدا ہوتا گیا جس کے ماتحت آج دُنیا کی بے شمار عجیب و غریب چیز میں اپنے
74
Page 75
اپنے دائرہ کے اندر کام کرتی ہوئی لوگوں کی عقول
کو محو حیرت کر رہی ہیں.لہذا یہ ایک
نادانی کا فعل ہے کہ مسئلہ ارتقاء سے خدا تعالیٰ کے خلاف استدلال کیا جائے بلکہ حق یہ
ہے کہ اس مسئلہ سے اُس کی پُر حکمت قدرتوں اور بے نظیر صنعت پر آگے سے بھی زیادہ
روشنی پڑ گئی ہے.باقی رہا دوسرا اعتراض یعنی یہ کہ دُنیا کی ہراک چیز اور ہر تغییر اور ہرسکون ایک
خاص قانون کے ماتحت ہے اور ہم اب دن بدن اس مخفی قانونِ قدرت کی زیادہ سے
زیادہ واقفیت حاصل کرتے جاتے ہیں اور اس بات پر زیادہ سے زیادہ روشنی پڑتی جاتی
ہے کہ دُنیا میں جو کچھ ہورہا ہے وہ نیچر کے کسی معین قانون کے ماتحت ہو رہا ہے جس سے
ثابت ہوا کہ جو کچھ ہے یہی قانون ہے خدا وغیرہ کوئی نہیں.سو یہ اعتراض بھی ایک
نہایت بودا اور کمزور اعتراض ہے.ہم نے کبھی بھی یہ دعوی نہیں کیا کہ دُنیا کسی قانون یا
سلسلہ اسباب کے ماتحت نہیں ہے اور بلا کسی درمیانی سبب کے اور بلا کسی قانون کے
خدا کے بلا واسطہ تصرف سے چل رہی ہے.ہم تو خود اس بات کے مقر بلکہ مدعی ہیں اور
اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ یہ تمام کارخانہ عالم ایک نہایت درجہ حکیمانہ قانون اور
بار یک در بار یک سلسلۂ اسباب کے ماتحت کام کر رہا ہے بلکہ اس دلیل میں ہم نے اس
قانون کو ہستی باری تعالیٰ کے ثبوت میں پیش کیا ہے.پس یہ ثابت کرنا کہ دنیا کی ہر چیز
ایک خاص معتین قانون کے ماتحت کام کر رہی ہے، ہمارے خلاف کوئی اثر نہیں رکھ
سکتا.سوال تو یہ ہے جس کا آج تک کوئی دہر یہ تسلی بخش جواب نہیں دے سکا کہ یہ
کامل و مکمل قانون کہاں سے آیا ہے ؟ بعض لوگ اس کا یہ جواب دیا کرتے ہیں کہ یہ
قانون مادہ کا طبعی خاصہ ہے اور نیز یہ کہ ایک قانون دوسرے قانون کے نتیجے میں پیدا
ہوتا ہے اور اسی طرح یہ سلسلہ چلتا چلا آیا ہے اور اسی طرح چلتا چلا جائے گا.مگر ہم کہتے
ہیں کہ یہ طبعی خاصہ کہاں سے آیا؟ اور پھر یہ کہ بیشک بعض اوقات ایک قانون دوسرے
75
Page 76
قانون کے نتیجہ میں پیدا ہوتا ہے لیکن بہر حال اس سبب اور مسبب کے سلسلہ کو خواہ کتنا
بھی لمبا کھینچا جائے آخر اس کی کوئی نہ کوئی ابتداء ماننی پڑیگی جس سے یہ سب کچھ نکلا
ہے.مثلاً سائنسدان کہتے ہیں کہ نیچر کا یہ ایک قانون ہے کہ زمین سورج کے اردگرد چکر
لگاتی ہے اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ قانون نتیجہ ہے نیچر کے ایک اور قانون کا کہ جب
ایک چیز پر دو یا دو سے زیادہ مختلف الجہت طاقتیں اثر ڈالتی ہیں تو وہ چیز ایک تیسری
جہت میں جو ان مختلف الجہت طاقتوں کے نتیجہ میں پیدا ہوتی ہے اور جسے انگریزی میں
ریز لٹنٹ (Resultant) کہتے ہیں حرکت کرنے لگ جاتی ہے اور زمین پر بھی چونکہ
مختلف الجہت طاقتیں اثر ڈال رہی ہیں اس لئے وہ ان طاقتوں کے نتیجہ میں ایک تیسری
جہت پر چل کر سورج کے گرد چکر کھانے لگ گئی ہے.ہم اس بات کو اصولاً مانتے ہیں،
لیکن ہمارا سوال پھر بھی اسی طرح قائم ہے کہ یہ اثر ڈالنے والی طاقتیں کہاں سے آئی
ہیں؟ اگر کہا جائے کہ یہ طاقتیں فلاں بات کے نتیجہ میں پیدا ہوئی ہیں تو پھر یہ سوال ہوگا
کہ یہ فلاں بات کہاں سے آئی ہے؟ الغرض موجودہ کا ئنات اور موجودہ نظام کا کوئی
ابتدائی تخم تسلیم کرنا پڑے گا جس کے اندر بالقوۃ طور پر وہ سارے کمالات اور قوانین اور
خواص موجود ماننے ہو نگے جو اس دنیا میں پائے جاتے ہیں.پس اس طرح بھی بحث
اسی نقطہ پر آگئی جس کا جواب او پر دیا جا چکا ہے.خلاصہ کلام یہ کہ ان درمیانی قوانین اور ان درمیانی تغییرات کو پیش کر کے خدا
کے وجود سے انکار کی راہ تلاش کرنا ایک دھوکے کا طریق ہے جس پر مغرب کے ایک
علم پسند طبقہ نے نہ معلوم کس طرح تسلی پارکھی ہے.ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ جوں جوں علمی
تحقیقاتوں میں ترقی ہوتی جاتی ہے اور قانون نیچر کے مخفی حقائق منکشف ہوتے جاتے
ہیں ، ہمارا دل عقلی طور پر زیادہ سے زیادہ بصیرت کے ساتھ اس ایمان پر قائم ہوتا جاتا
ہے کہ یہ کارخانہ عالم مع اپنے نہایت درجہ حکیمانہ قانون کے ضرور کسی خالق و مالک.76
Page 77
ہم وحکیم.قدیر و متصرف ہستی کے ماتحت چل رہا ہے.اگر ایک معمولی چیز کو دیکھ کر ہم
اس نتیجہ پر پہنچ سکتے ہیں کہ وہ کسی صانع کی پیدا کردہ ہے تو ایک عجیب و غریب پر حکمت
چیز کو دیکھ کر بدرجہ اولیٰ ہمارے اندر یہ ایمان پیدا ہونا چاہیے کہ وہ خود بخود نہیں بلکہ کسی
بالا ہستی کی قدرت نمائی کا کرشمہ ہے.میرے عزیز و ! خوب غور کرو کہ ان نئے علوم اور نئی
تحقیقاتوں کا سوائے اس کے اور کوئی اثر نہیں ہوسکتا کہ یہ ثابت ہو کہ دُنیا ومافیہا کا
قانون اس سے بہت بڑھ چڑھ کر مفصل اور حکیمانہ ہے جو اس زمانہ سے پہلے سمجھا جاتا
تھا اور یہ کہ دُنیا کی مختلف چیزیں صرف اپنے الگ الگ قانون ہی کے ماتحت نہیں بلکہ
بحیثیت مجموعی بھی ایک نہایت حکیمانہ قانون کی لڑی میں پروئی ہوئی ہیں اور ایک
دوسرے پر عجیب وغریب رنگ میں اثر ڈالتی رہتی ہیں اور نیز یہ کہ دنیا کی کوئی چیز فضول
اور زائد نہیں بلکہ ہر اک اپنے اپنے حلقہ میں اپنے اپنے قانون کے ماتحت اپنا اپنا کام کر
رہی ہے.مگر یہ انکشاف اگر اسے انکشاف کہا جاوے ہماری تائید میں ہے نہ کہ ہمارے
مخالف.کیونکہ اس سے خدا کے خلاف کوئی دلیل نہیں پکڑی جاسکتی بلکہ اس سے ہمارے
خدا کی حکیمانہ قدرتوں کے کرشموں کا بیش از پیش اظہار ہوتا چلا جاتا ہے.لیکن حق یہ ہے کہ اُصولی طور پر یہ انکشاف کوئی نیا انکشاف نہیں بلکہ
قرآن شریف آج سے تیرہ سو سال قبل اجمالاً اس حقیقت کو آشکار کر چکا ہے.چنانچہ
فرماتا ہے:
أَوَلَمْ يَرَوْ إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْي ءٍ يَتَفَيَّوُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِيْنِ وَ الشَّمَائِلِ
سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُوْنَ.وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَواتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِيْنَ
سورة النحل.آیات 50،49
77
سورة الأنبياء - آيت 17
Page 78
یعنی ” کیا لوگ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی طرف نہیں دیکھتے کہ کس طرح دُنیا کی ہر چیز
خدا کے حکم کے ماتحت مطیع و فرمانبردار ہو کر اپنے دائیں اور بائیں اثر ڈال رہی ہے اور
جو کچھ کہ زمین و آسمان میں ہے وہ سب خدا کے مقرر کردہ قانون کے ماتحت چل رہا
ہے.اور ہم نے زمین و آسمان
کو اور جو کچھ کہ اُن میں ہے محض تفریح کے طور پر بلا مقصد
نہیں پیدا کیا بلکہ ایک خاص مقصد کے ماتحت پیدا کیا ہے.“
یہ وہ حقیقت ہے جس کی تفصیلات کی دریافت کے واسطے یورپ و امریکہ کے
محققین آج اپنی عمر میں صرف کر رہے ہیں لیکن بوجہ اس کے کہ اُن کی دین کی آنکھ بند
ہے اُن میں سے بعض اپنی بدقسمتی سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ اُن کی یہ تحقیقا تیں مذہب اور
خدا کے وجود پر ایک حملہ ہیں حالانکہ حق یہ ہے کہ نظام عالم اور قانون نیچر کا جتنا بھی کمال
ظاہر ہوتا جاتا ہے اتنا ہی یہ عالم سفلی اہل بصیرت کے نزدیک ایک حکیم و علیم ، قدیر
و متصرف خالق کی طرف اشارہ کرنے میں زیادہ وضاحت اختیار کرتا جاتا ہے.چنانچہ
خود مغربی محققین میں بھی ایک کافی طبقہ ان لوگوں کا ہے جو خدا پر ایمان لاتے ہیں اور یہ
جدید تحقیقا تیں اُن کے اس ایمان کے رستہ میں قطعاً کوئی روک نہیں ہوتیں بلکہ انہیں وہ
دہریت کے خلاف بطور ایک حربہ کے استعمال کرتے ہیں.پس اے میرے عزیز و ا تم
ان علوم جدیدہ سے مت گھبراؤ کیونکہ یہ سب تمہارے خادم ہیں اور ان کا سوائے اس
کے اور کوئی اثر نہیں کہ تمہارے خدا کی حکیمانہ قدرت نمایوں کے کرشمے زیادہ سے زیادہ
وضاحت اور تعیین کے ساتھ لوگوں کی نظروں کے سامنے آتے جاتے ہیں اور دنیا پر یہ
بات علم الیقین کے طور پر ثابت ہوتی چلی جارہی ہے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے
بالواسطہ یا بلا واسطہ انسان کے فائدہ کے لئے ہے جیسا کہ آج سے تیرہ سو سال قبل
قرآن شریف فرما چکا ہے:.78
Page 79
هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً
وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِى السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ.یعنی ” جو کچھ دُنیا میں ہے خواہ زمین میں یا آسمانوں میں وہ سب تمہارے فائدہ
کے لئے پیدا کیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں
کو تمہارے لئے مسخر کر رکھا ہے
تا کہ تم اُن کے حقائق سے آگاہ ہو کر اُن سے فائدہ اُٹھاؤ.“
مگر افسوس انسان پر کہ جن چیزوں کو اُن کے آقا و مالک نے اُس کی ہدایت اور
ترقی کے لئے پیدا کیا تھا انہی کو اُس نے اپنی گمراہی اور ہلاکت کا سبب بنالیا.قتل
الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ.یقینا یہ ناشکری انسان
کو تباہی کے سوا کسی اور طرف نہیں لے
جاسکتی.اس جگہ یہ بات بھی یاد رکھنی چاہئے کہ دراصل یہ سوال کہ کوئی خدا موجود ہے یا
نہیں ،سائنس کے حقیقی دائرہ عمل سے باہر ہے اور کوئی سائنسدان اپنے دائرہ کے اندر
رہتے ہوئے اس بحث میں نہیں پڑ سکتا.کیونکہ سائنس مادیات کے خواص اور قوانین
کے دریافت کرنے کا علم ہے اور غیر مادی اشیاء کی بحث یا زیادہ صیح طور پر یوں کہہ سکتے
ہیں کہ ماوراء المادیات (Metaphysics) کی بحث کم از کم سائنس کے موجودہ
دائرہ عمل سے باہر ہے.علاوہ ازیں سائنس کو بالعموم اس بات سے تعلق نہیں کہ کونسی چیز
نہیں ہے بلکہ اُسے زیادہ تر اس بات سے سروکار ہے کہ کونسی چیز ہے اور پھر یہ کہ جو چیز
ہے وہ کیا ہے اور کس قانون کے ماتحت ہے.پس یہ حقیقت کہ خدا نہیں ہے کم از کم
موجودہ سائنس کی بحث سے خارج ہے.ہاں البتہ یہ بحث سائنس کے دائرہ عمل میں
آسکتی ہے کہ یہ دنیا اور اس کی چیزیں کس طرح عالم وجود میں آئی ہیں اور حیات کا آغاز
کس طرح ہوا ہے وغیر ذالک.پس سائنس دان زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم
سورة البقرة - ايت 30 ٢ سورة الجاثیه ایت 14 ٣ سورة عبس.ایت18
79
Page 80
نے اس بات کا پتہ لگا لیا ہے کہ دنیا ہمیشہ سے ہے اور یہ کہ نظامِ عالم خود بخود ایک
سلسله قانون کے ماتحت جاری ہے اور یہ قانون بھی خود بخود ہی چل رہا ہے اور حیات کا بھی
خود بخود آغاز ہو گیا ہے اور اس تحقیق سے نتیجہ وہ یہ عقلی استدلال کر سکتے ہیں کہ کوئی خدا نہیں
ہے.مگر خدا کا نہ ہونا خود اپنی ذات میں بلاواسطہ طور پر سائنس
کی تحقیق میں داخل نہیں.علاوہ ازیں ایک اور بات بھی یادر کھنے کے قابل ہے اور وہ یہ کہ بد قسمتی سے لوگ
سائنس کے متعلق عموماً ایک خطرناک غلطی میں مبتلا ہیں.یعنی وہ سائنسدانوں کے
قیاسات اور سائنس کے ثابت شدہ حقائق میں تمیز نہیں کرتے.ظاہر ہے کہ
سائنسدانوں کے اعلانات تین قسموں میں منقسم ہوتے ہیں:.(اول) سائنس دانوں کے قیاسات
( دوم )سائنس کے نامکمل تجر بات.اور
( سوم ) سائنس کے ثابت شدہ حقائق.یہ تینوں الگ الگ حیثیت اور الگ الگ درجہ رکھتے ہیں اور انہیں ایک ساوزن
دینا خطرناک غلطی ہے.مگر نا واقف لوگ ان سب کو ایک سا درجہ دے دیتے ہیں اور ہر
ایک بات کو جو سائنس دانوں کے منہ سے نکلتی ہے اور ہر ایک خیال کو جس کا اُن کی طرف
سے اظہار کیا جاتا ہے اور اسی طرح تمام ان نامکمل تجربات اور مشاہدات کو جن کا
سائنس دانوں کی طرف سے اعلان ہوتا رہتا ہے سائنس کے ثابت شدہ حقائق قرار
دے لیتے ہیں اور اس طرح صداقت کی اتباع اختیار کرنے کی بجائے اپنی جہالت سے
سائنسدانوں کی شخصی غلامی کا طوق اپنے گلے میں ڈال لیتے ہیں.حالانکہ ہر شخص جو تھوڑا
بہت علم رکھتا ہے جانتا ہے کہ سائنس کے ثابت شدہ حقائق صرف وہی قرار دیئے جاسکتے
ہیں کہ جو مختلف سائنسدانوں کے ہاتھ پر بار بار کے تجربات سے روز روشن کی طرح
مشاہدہ میں آچکے ہیں اور آتے رہتے ہیں اور جن کی حقیقت علمی طور پر بھی سبب اور
80
Page 81
مسبب کے رنگ میں قطعی طور پر ثابت و قائم ہوچکی ہے.مگر ان کے علاوہ سائنس دانوں
کے جو باقی خیالات یا تھیوریاں ہیں یا جو اُن کے نامکمل تجربات ہیں وہ ہرگز ثابت شدہ
حقائق نہیں کہلا سکتے کیونکہ اُن میں اتنا ہی غلطی کا احتمال ہے جو دوسرے سمجھدار اور دانا
لوگوں کی باتوں کے متعلق ہوتا ہے.حقیقت یہ ہے کہ جب کوئی نئی بات سائنس کے
تجربات کی رو سے عملی مشاہدہ میں آکر دریافت ہوتی ہے اور پھر مختلف لوگوں کے بار بار
تجربات سے جو مختلف حالات کے ماتحت کئے جاتے ہیں وہ پایہ ثبوت کو پہنچتی ہے اور
علمی طور پر بھی اس کے کسی پہلو کے متعلق تاریکی نہیں رہتی تو تب جا کر وہ ایک
ثابت شدہ حقیقت سمجھی جاتی ہے اور اس مرحلہ سے قبل گوسائنس کے بعد تجربات سے
اُس پر روشنی پڑتی ہو اور بعض سائنسدان اس کے قائل بھی ہو گئے ہوں مگر وہ ایک ثابت
شدہ حقیقت قرار نہیں دی جاسکتی.لیکن بد قسمتی سے عوام الناس ان ہر دو قسم کی باتوں میں
تمیز نہیں کرتے.اور سب کو ہی سائنس کے ثابت شدہ حقائق سمجھ کر ان کے آگے سر تسلیم
خم کر دیتے ہیں.اور اس سے بھی بڑھ کر اندھیر یہ ہے کہ سائنس کی تحقیقاتوں کی بنا پر جو
خیالات اور تھیوریاں سائنسدان قائم کرتے ہیں وہ بھی سائنس کے ثابت شدہ حقائق
قرار دے لئے جاتے ہیں گویا تین مختلف چیزوں کو جو ایک دوسرے سے بالکل ممتاز و
متغائر ہیں مخلوط کر دیا جاتا ہے اور اس طرح پر سائنس جس کا کام نسلِ انسانی کے دماغوں
کو علمی روشنی پہنچانا ہے بعض اوقات جہالت اور تاریکی کا موجب ہو جاتی ہے.ظاہر ہے کہ جب کوئی بات سائنس کے تجربات اور مشاہدات کی رُو سے
پایہ ثبوت کو پہنچتی ہے تو پھر اُس کی بنا پر طبعا دنیا کے علمی طبقہ میں ایک حرکت پیدا ہوتی
ہے اور مختلف سائنسدان اس جدید تحقیق کی روشنی میں مختلف خیالات
اور مختلف تھیوریاں
قائم کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس طرح ہر جدید تحقیق کے ساتھ جدید خیالات اور
جدید تھیوریوں کا وجود بھی پیدا ہوتا جاتا ہے اور ناواقف لوگ سائنس کے لفظ سے
81
Page 82
مرعوب ہو کر یا کسی اور وجہ سے اس سارے رطب و یابس کے
مجموعہ کو ہی سائنس کی
ثابت شدہ حقیقت قرار دینے لگ جاتے ہیں.حالانکہ اصل ثابت شدہ حقیقت بہت
تھوڑی ہوتی ہے اور باقی سب سائنسدانوں کی تھیوریاں اور قیاسات اور خیالات
ہوتے ہیں جو نہ صرف یہ کہ آئے دن بدلتے رہتے ہیں بلکہ ان کے متعلق خود
سائنسدانوں میں بھی ہمیشہ اختلاف رہتا ہے.الغرض یہ ایک خطرناک غلطی ہے کہ
(اوّل) سائنسدانوں کے قیاسات اور (دوم) سائنس دانوں کے نامکمل تجربات اور
(سوم) سائنس کے ثابت شدہ حقائق میں فرق نہیں کیا جاتا.بلکہ ہر اک بات جو کسی
سائنسدان کے منہ یا قلم سے نکلتی ہے اس کے سامنے غلاموں کی طرح گردنیں جھکا دی
جاتی ہیں اور بدقسمتی سے یہ ذہنی اور علمی غلامی زیادہ تر مشرقی لوگوں کے ہی حصہ میں آئی
ہے ورنہ خود یورپ اور امریکہ والے عموماً ان باتوں میں امتیاز ملحوظ رکھتے ہیں اور سائنس
کے حقائق صرف انہی باتوں کو قرار دیتے ہیں جو واقعی بار بار کے تجربات سے مشاہدہ
میں آچکی ہیں اور علمی طور پر بھی اُن کے متعلق کوئی تاریکی کا پہلو نہیں رہا.اب اگر اس اصل کے ماتحت سوال زیر بحث پر نظر ڈالی جائے تو سائنس کی کوئی
ثابت شدہ حقیقت بھی ایسی نظر نہیں آتی جس کی بنا پر ہستی باری تعالیٰ کے متعلق کوئی
اعتراض وارد ہو سکتا ہو اور اس کا ادنیٰ ثبوت یہ ہے کہ جب کوئی جدید تحقیق واقعی
پایہ ثبوت کو پہنچ جاتی ہے تو پھر کوئی سائنسدان اس کا منکر نہیں رہ سکتا.کیونکہ پایہ ثبوت کو
پہنچنے کے یہ معنے ہیں کہ وہ نہ صرف علمی طور پر یقین کی حد کو پہنچ جائے بلکہ بار بار کے
تجربات سے جو مختلف حالات کے ماتحت کئے گئے ہوں اس کا ایسے رنگ میں عملی مشاہدہ
بھی ہو جائے کہ پھر اس میں شک وشبہ کی کوئی گنجائش نہ رہے.اور ظاہر ہے کہ اس مقام
پر پہنچ کرکوئی سائنسدان بلکہ کوئی شخص بھی جو تھوڑا بہت شعور رکھتا ہے اس
کا منکر نہیں رہ
سکتا.اور عملاً بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سائنس کی ہر ثابت شدہ حقیقت تمام سائنسدانوں کے
82
Page 83
نزدیک مسلم ہے اور ان باتوں کے متعلق کسی کو اختلاف نہیں بلکہ اختلاف صرف انہی
باتوں میں ہے جو یا تو ابھی تک پوری طرح ثابت نہیں ہوئیں اور یا پھر بعض
سائنسدانوں کے خیالات اور قیاسات ہیں جو انہوں نے ثابت شدہ حقائق کی بنا پر عقلی
استدلالات کر کر کے تھیوریوں کی صورت میں قائم کئے ہیں.الغرض سائنس کے ثابت شدہ حقائق کے متعلق قطعاً کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا،
لیکن ہستی باری تعالیٰ کے عقیدہ کے متعلق ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے سائنسدان خدا کے
قائل ہیں بلکہ دراصل اگر دیکھا جائے تو بہت تھوڑے اِن میں سے ایسے ہیں کہ جو خُدا کا
انکار کرتے ہیں اور زیادہ وہ ہیں کہ جو انکار نہیں کرتے.پس ثابت ہوا کہ سائنس کی کوئی
ثابت شدہ حقیقت ایسی نہیں ہے کہ جس سے یہ یقینی استدلال ہو سکے کہ یہ کارخانہ عالم خود
بخود بغیر کسی خالق و مالک کے چل رہا ہے ورنہ سائنسدانوں میں یہ اختلاف نہ ہوتا.اور اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اگر آئندہ زمانہ میں کوئی ایسی بات ثابت ہو جائے جس
سے یہ پتہ لگے کہ یہ دنیا ومافیہا خود اپنے آپ سے ہی ہے اور خود بخودہی چل رہی ہے تو
پھر کیا جواب ہوگا ؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اول تو اس قسم کا خیال ہی فضول بلکہ محض طفلانہ
ہے کہ اگر یہ ہو جائے تو کیا ہوگا اور وہ ہو جائے تو کیا ہوگا، لیکن اگر اس سوال کو خواہ نخواہ
پیدا ہی کرنا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم تو صداقت کے طالب ہیں جو بات بھی واقعی اور حقیقی
طور پر ثابت ہو جائے ہمیں اس سے انکار نہیں ہوسکتا.ہمارے رسول ﷺ ( فداہ
نفسی) کو فرما تا ہے کہ تم میچوں سے کہد و کہ خدا کا کوئی بیٹا نہیں ہے بلکہ اس کا
کوئی بیٹا مانا ایسا باطل اور خطر ناک فعل ہے کہ قریب ہے کہ اس سے زمین و آسمان
تہ و بالا ہو جائیں لیکن با ینہمہ مسیحیوں سے یہ بھی کہد و کہ اگر خدا کا کوئی بیٹا ثابت ہو تو آنا
اَوَّلُ الْعَابِدِيْنَ " یعنی " اس صورت میں میں سب سے پہلا شخص اس کی عبادت کرنے
سورة الزخرف.آیت 82
83
Page 84
والا ہونگا.پس صداقت کی پیاس تو ہماری گھٹی میں ہے جو ہمارے پیارے رسول سے
ہمیں ورثہ میں ملی ہے.لہذا اُصولی جواب تو ہمارا یہ ہے کہ جو بات بھی واقعی اور حقیقی طور
پر ثابت ہوگی ہم اس پر ایمان لائیں گے خواہ وہ کچھ ہو.لیکن حقیقی جواب یہ ہے کہ ایسی
کوئی بات ہرگز ثابت نہیں ہو سکے گی جو خدا تعالیٰ کے وجود کو شک و شبہ میں ڈال دے
کیونکہ ایسی بات کے ثابت ہونے کے یہ معنی ہیں کہ دو ثابت شدہ حقائق آپس میں
ٹکرانے لگیں جو بالبداہت ناممکن ہے.کیا ایسا ہوسکتا ہے کہ مثلاً سائنس کی رُو سے ایک
طرف تو یہ ثابت ہو کہ مقناطیس لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور پھر سائنس کی رُو سے ہی
دوسری طرف یہ ثابت ہو کہ اسی قسم کے حالات میں مقناطیس لوہے کو اپنی طرف نہیں
کھینچتا ؟ ظاہر ہے کہ ایسا ہر گز نہیں ہو سکتا اور اگر کبھی بفرض محال ہمیں ایسا نظر آئے گا تو
ہمیں ان دو حقیقتوں میں سے ایک کو غلط قرار دینا پڑے گا یعنی ایک کے متعلق یہ ماننا
پڑے گا کہ وہ دراصل کوئی ثابت شدہ حقیقت نہیں ہے بلکہ اُسے غلطی سے ایسا سمجھ لیا گیا
ہے.پس اگر بفرض محال
کبھی سائنس کی کوئی ایسی تحقیق ثابت بھی ہو جس سے یہ پتہ
لگے کہ دُنیا کی یہ سب چیزیں خود بخود ہمیشہ سے ہیں اور خود بخودہی یہ سارا نظام چل رہا
ہے تو پھر بھی ہم صرف اس وجہ سے ہرگز خدا کا انکار نہیں کرینگے کیونکہ اگر یہ تحقیق سائنس
کی تحقیق ہوگی تو خدا کا وجود بھی تو اصولاً سائنس کے طریق سے ہی پایہ ثبوت کو پہنچا ہؤا
ہے.اور کوئی وجہ نہیں کہ ہم ایک نام نہاد تحقیق کی وجہ سے دوسری ثابت شدہ حقیقت کو
جس کی صداقت پر ابتداء آفرنیش سے مشاہدہ کی صورت میں مہر لگتی چلی آئی ہے ترک کر
دیں بلکہ اس صورت میں ہم پہلے یہ غور کرینگے کہ یہ جدید تحقیق جسے سائنس کی ثابت شدہ
حقیقت قرار دیا جاتا ہے کہاں تک درست اور قابل قبول ہے.خوب غور کرو کہ سائنس کے حقائق کی پختگی صرف اس بنا پر تسلیم کی جاتی ہے کہ
اس میں علاوہ علمی اور عقلی دلائل کے تجربہ اور مشاہدہ پر بنا ہوتی ہے.اور یہ ظاہر ہے کہ
84
Page 85
جب عقلی دلائل کے ساتھ تجربہ اور مشاہدہ مل جاتا ہے تو پھر کوئی غلطی کا احتمال (سوائے
اس کے کہ مشاہدہ ناقص ہو ) نہیں رہتا اور واقعی یہ طریق تحقیق بہترین طریق ہے اور
اسی لئے دنیوی علوم میں سائنس کے ثابت شدہ حقائق اپنی پختگی میں سب پر فائق سمجھے
جاتے ہیں.لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جن دلائل کے ساتھ اس دنیا میں خدا کا وجود ثابت ہوتا
ہے وہ بھی اسی سائنس والے طریق پر مبنی ہیں کیونکہ جیسا کہ ہم نے اوپر بیان کیا ہے خدا
کا وجود صرف عقلی دلائل سے ہی ثابت نہیں ہوتا بلکہ سائنس کے حقائق کی طرح اس کی بنا
بھی تجربہ اور مشاہدہ پر ہے بلکہ یہ تجربہ اور مشاہدہ اپنی کمیت اور کیفیت میں سائنس کے
حقائق سے بہت بڑھا ہوا ہے.عقل کی پہنچ تو صرف اس حد تک ہے کہ یہ ثابت کرے
کہ کوئی خدا ہونا چاہئے“ اور اس سے اوپر کا مقام کہ واقعی ” خد ا موجود ہے تجربہ اور
مشاہدہ کے ذریعہ سے حاصل ہوتا ہے اور اس تجربہ اور مشاہدہ کا سامان خود ذاتِ باری
تعالیٰ کی طرف سے پیدا کیا جاتا ہے.جیسا کہ فرمایا:
لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ.یعنی ” خدا تک انسان کی آنکھ نہیں پہنچ سکتی ( یعنی صرف عقلی دلائل سے خُدا کا
عرفان حاصل نہیں ہو سکتا ) لیکن خُداخود انسانی آنکھ تک پہنچتا ہے.“
یعنی اپنی طرف سے وہ ایسے سامان پیدا کرتا ہے کہ انسان کو خُدا کا مشاہدہ
ہو سکے تا اُس کا عرفان ناقص نہ رہے.اور یہ سوال کہ یہ مشاہدہ کس طرح ہو سکتا ہے ایک
لمبا سوال ہے جس کا مفصل جواب اس کتاب کے دوسرے حصہ سے تعلق رکھتا ہے مگر
اس جگہ مختصراً اس قدر اشارہ کافی ہے کہ یہ مشاہدہ اس کلام کے ذریعہ سے حاصل ہوتا ہے
جو خدا تعالیٰ اپنے پاک بندوں پر نازل فرماتا ہے جو خدائی نشانوں سے اس طرح معمور
ہوتا ہے جس طرح ایک اچھا شمر دار درخت پھل کے موسم میں پھل سے لدا ہو ا ہوتا ہے
سورة الأنعام آيت 104
85
Page 86
اور جس طرح پھل کے چکھنے کے بعد کوئی شخص درخت کی شناخت میں شبہ نہیں کر سکتا.اسی طرح اس رُوحانی پھل کے ذائقہ کرنے کے بعد خدا کا وجود بھی روز روشن کی طرح
انسانی آنکھوں کے سامنے آجاتا ہے.بہر حال خدا کے وجود کا ثبوت بھی سائنس کے حقائق کی طرح ( گو اپنے کمال کی
حالت میں وضاحت میں ان سے بہت بڑھ چڑھ کر ) عقلی دلائل کے علاوہ تجربہ اور
مشاہدہ پر مبنی ہے.پس اگر بفرض محال سائنس کی کوئی ایسی تحقیق ثابت بھی ہو جو ہستی
باری تعالیٰ کے خلاف نظر آئے تو پھر بھی ہم خدا کا انکار نہیں کرینگے بلکہ پھر ہم اس جدید
تحقیق کے متعلق غور کریں گے کہ وہ کہاں تک درست اور قابل قبول ہے.اور ہمارے
نزدیک اس غور کا نتیجہ سوائے اس کے اور کوئی نہیں ہوسکتا کہ یہ بات ثابت ہو کہ خدا کا
وجود برحق ہے اور سائنس کی یہ نام نہاد تحقیق جو اس کے خلاف نظر آتی ہے وہ یا تو
در حقیقت اس کے خلاف نہیں ہے اور یا پھر کسی ناقص مشاہدہ پر مبنی ہو کر غلط طور پر ثابت
شدہ حقیقت قرار دے لی گئی ہے ورنہ دراصل وہ کوئی ثابت شدہ حقیقت نہیں.دراصل بات یہ ہے جیسا کہ آگے چل کر ثابت کیا جائے گا کہ خُدا کا وجود ایسے
کامل واکمل مشاہدہ سے پایہ ثبوت
کو پہنچا ہوا ہے کہ اس کے متعلق یہ کہنا کہ سائنس کی کوئی
حقیقی تحقیق اس کے خلاف بھی ہو سکتی ہے دو متضاد باتوں کو ایک جگہ جمع کرنا ہے جو ناممکن
ہے.سائنس اگر ہمارے مشاہدہ پر حملہ کرے تو وہ اپنی جڑھ پر خود اپنے ہاتھ سے کلہاڑا
چلانے والی ٹھہرے گی کیونکہ اس کی اپنی بنیاد مشاہدہ پر ہے.خیر یہ تو ایک زائد اور
پیش از وقت سوال ہے کیونکہ آئندہ جو کچھ ہوگا وہ آئندہ دیکھا جائے گالیکن اس بات
میں قطعاً کوئی شک نہیں کہ اس وقت تک سائنس کی کوئی ثابت شدہ حقیقت ایسی نہیں
ہے جو معقولی طور پر ہستی باری تعالیٰ کے خلاف پیش کی جاسکے.اور حق یہی ہے اور یہی
رہیگا کہ یہ دُنیا مع اپنی بے شمار مختلف الصورت عجیب و غریب چیزوں کے اور مع اپنے
86
Page 87
اس نہایت درجہ حکیمانہ قانون کے جو اس کی ہر چیز میں کام کرتا ہوا نظر آتا ہے اور مع
اپنے اس حیرت انگیز نظام کے جس نے اس کی بے شمار مختلف الخواص چیزوں کو ایک
واحد لڑی میں پرو رکھا ہے اور جس کی وجہ سے دُنیا کی ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کی
ضروریات کے مہیا کرنے کے لئے ہزاروں یا لاکھوں یا کروڑوں میل کے فاصلہ پر بے
شمار قدرتی کارخانے دن رات کام میں لگے ہوئے نظر آتے ہیں اس بات کا ایک
زبر دست ثبوت ہے کہ اس دنیا کے اوپر ایک حکیم ولیم و قدیر و متصرف ہستی کام کر رہی
ہے جس کے قبضہ قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں.فلسفہ جدید کیوں ٹھوکر کا موجب بن رہا ہے؟
اس بحث کو ختم کرنے سے قبل میں یہ بات بھی مختصر طور پر بیان کرنا چاہتا ہوں کہ
وجہ کیا ہے کہ جبکہ یورپ کا جدید فلسفہ یا بعض سائنسدانوں کے قیاسات قطع نظر اس کے
کہ وہ صحیح ہیں یا غلط یا کس حد تک صحیح ہیں اور کس حد تک غلط خدا تعالیٰ کی ہستی کے متعلق
حقیقتاً اعتراض کا موجب نہیں ہو سکتے ، وہ اس زمانہ میں بہت سے لوگوں کے لئے ٹھوکر کا
موجب بن رہے ہیں.سو جاننا چاہئے کہ یورپ کے جدید نظریات نے دو وجہ سے
لوگوں کو غلطی میں ڈالا ہے.پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جب مغربی محققین نے یہ خیال پیدا کیا
که ماده خود اپنی ذات کے اندر یہ خاصیت رکھتا ہے کہ وہ مختلف صورتیں اختیار کر لے اور
ادفی حالت سے اعلیٰ کی طرف ترقی کرتا چلا جائے اور یہ کہ موجودہ دنیا کی سب چیزیں
اور خصوصاً انسان اسی قانون ارتقاء کی صنعت کا کرشمہ ہیں تو بوجہ اس کے کہ ان کو روحانی
طور پر ذات باری تعالیٰ کے متعلق کوئی بصیرت حاصل نہیں تھی اُن کے دل میں یہ مجبہ پیدا
ہونے لگا کہ شاید دنیا کے اوپر کوئی الگ خدا نہ ہو بلکہ یہ دنیا اپنے آپ سے ہی ہو اور مادہ
کے اندرونی خواص کے نتیجے میں ہی یہ سارا کارخانہ چلتا چلا جارہا ہو.چنانچہ بالآخر وہ
87
Page 88
اسی خیال پر قائم ہو گئے کہ یہ دنیا ایک مشین کے طور پر چل رہی ہے اور دُنیا کے یہ سارے
تغیرات اور نظائر اسی اندرونی میکینزم (Mechanism) یعنی اندرونی صنعت کا نتیجہ
ہیں وغیرہ وغیرہ.اس شبہ کا جواب اوپر دیا جا چکا ہے کہ اگر غور سے دیکھا جاوے تو جس رنگ کا
قانونِ صنعت دُنیا میں پایا جاتا ہے وہ خود اس بات کو چاہتا ہے کہ دنیا کے اوپر ایک الگ
بالا ہستی کے وجود کو مانا جائے جس نے اس نہایت حکیمانہ قانون کو مادہ میں ودیعت کر
رکھا ہے اور پھر مادہ اپنے حالات وکوائف سے بھی ایک خالق و مالک ہستی کو چاہتا ہے.اور پھر یہ بھی بتایا جا چکا ہے کہ دنیا میں صرف میکینزم (Mechanism) ہی نہیں ہے
بلکہ نیچر کے مطالعہ سے پتہ لگتا ہے کہ دُنیا میں ایک خاص ترتیب یعنی ڈیزائن
(Design) اور ایک علت غائی یعنی ٹیلی آلوجی (Teleology) بھی پائی جاتی ہے
اور یہ سب باتیں ایک مستقل مدرک بالا رادہ خالق و مالک ہستی کی طرف اشارہ کر رہی
ہیں.چنانچہ آگے چل کر اس بات کو مزید وضاحت کے ساتھ بیان کیا جائے گا.دوسری بات جس کی وجہ سے یورپ کا جدید فلسفہ بعض لوگوں کے لئے ٹھوکر کا
موجب بن گیا ہے یہ ہے کہ مسئلہ ارتقاء نے خلق عالم اور خصوصاً خلق انسان کو ایسے
رنگ میں پیش کیا ہے جو اس زمانہ کے معروف الہامی مذاہب کی عرفی تعلیم کے خلاف
نظر آتا ہے اور یہ طبعی امر ہے کہ جب کسی الہامی مذہب پر کوئی ایسا حملہ ہو جو اُس کی صحت
کولوگوں کی نظر میں مشتبہ کر دے اور انسان اُس کے جواب اور حل کی طاقت نہ رکھتا ہو تو
طبعا وہ خدا کی ہستی کے متعلق شکوک و شبہات میں مبتلا ہونے لگتا ہے اور بزعم خود یہ سمجھنے
لگتا ہے کہ جب وہ بات بھی جو خدا کی طرف منسوب کی جاتی تھی غلط نکلی تو پھر یہ سب
کارخانہ مذہب کا باطل ہے اور خدا بھی ایک خیال موہوم کے سوا کچھ نہیں.بعینہ یہی
صورت مسئلہ ارتقاء کے متعلق اس زمانہ کے لوگوں کو پیش آئی ہے.مسیحی لوگ اپنے
88
Page 89
پادریوں سے اور مسلمان اپنے مولویوں سے اور ہندو اپنے پنڈتوں سے اور دوسرے
لوگ اپنے دینی علماء سے یہ سنتے تھے کہ پہلے سب دھو آں یا پانی تھا اور اس دھوئیں یا پانی
سے خدا نے یہ گونا گوں چیزیں پیدا کیں اور یہ کہ خدا نے یہ زمین اور آسمان اور ان کے
درمیان کی چیزیں چوبیس گھنٹے والے چھ دنوں میں پیدا کیں اور پھر اُس نے ایک مٹی کا
بُت بنا کر اُس کے اندر پھونک ماری تو حضرت آدم پیدا ہو گئے اور اُن کی پسلی سے
حضرت تو انکل آئیں اور پھر ان دونوں کی نسل آگے چلنی شروع ہوگئی اور یہ سلسلہ انسانی
نسل کا سات ہزار سال سے جاری ہے اور پھر بعض کے نزدیک یہ کہ ابتداء خدا کے
ما تحت مادہ نے انڈے کی صورت اختیار کی.اور یہ انڈا پھٹ کر دو حصوں میں ہو گیا جس
سے ایک طرف زمین بن گئی اور دوسری طرف آسمان بن گیا.اور یہ کہ مرد و عورت خدا
کے وجود سے نکل کر ظاہر ہو گئے.یا یہ کہ خدا کو پسینہ آیا اور پسینے کے قطروں سے یہ سارا
عالم پیدا ہو گیا وغیر ذالک.اس قسم کی باتیں پیدائش عالم کے متعلق لوگ اپنے پادریوں
اور مولویوں اور پنڈتوں وغیرہ سے سُن رہے تھے کہ اچانک اُن کے کانوں میں یہ آواز
پڑی کہ سائنس کی تحقیقات سے یہ سارے قصے جھوٹے ثابت ہوگئے ہیں اور حق یہ ہے
کہ یہ سارا عجائب خانہ عالم مادہ کے ارتقائی خواص سے ظہور میں آیا ہے اور لاکھوں اور
کروڑوں سال کے عرصہ میں ہر ایک چیز ادنیٰ حالت سے ترقی کر کر کے اعلیٰ حالت کو
پہنچی ہے اور انسان بھی اسی ارتقاء کا کرشمہ ہے وغیر ذالک.بس پھر کیا تھا لوگ مذہب کی
طرف سے بدظن ہو گئے اور سائنس کی نئی روشنی نے ان کی آنکھوں کو خیرہ کرنا شروع
کر دیا اور وہ ایسے بدحواس ہو کر بھاگے کہ خدا کا عقیدہ بھی اپنے پیچھے چھوڑ گئے.مذہب کی اس شرمناک ہنریت کی سب سے زیادہ ذمہ داری مغرب کے مسیحی
ادریوں پر ہے کیونکہ جدید فلسفہ و سائنس کی آواز سب سے پہلے انہی کے کانوں میں
پہنچی اور انہوں نے اس آواز سے بدحواس ہو کر ایسی ایسی مذبوحی حرکات کیں کہ دیکھنے
89
Page 90
والوں پر اُن کی مذبوحیت آشکار ہوگئی اور ہزاروں لاکھوں انسانوں نے پادریوں کی اس
حالت
کو دیکھ کر اور اپنے آپ کو بھی بے بس پا کردہریت کا راستہ اختیار کر لیا.جس کا
نتیجہ یہ ہوا کہ جب یہی آواز کسی دوسری قوم تک پہنچی تو اس احساس سے کہ ایک مذہبی
دستہ پہلے ہی اس حملہ کے سامنے پسپا ہو چکا ہے اُن میں سے بھی بعض لوگوں نے ہمت
ہار دی.اور اس طرح ہر پہلی شکست بعد کی شکست کے لئے راستہ صاف کرتی گئی.حالانکہ اگر لوگ ذرا غور وفکر سے کام لیتے تو بات نہایت معمولی تھی کیونکہ اول تو بہت
سے خیالات جو اس وقت مختلف مذاہب کے متبعین میں خلق عالم اور خلق آدم کے متعلق
پائے جاتے ہیں وہ دراصل بعد کے علماء کے اپنے حواشی ہیں اور ان مذاہب کی اصل
الہامی کتب یا دیگر مستند کتابوں میں ان کا کوئی پتہ نہیں چلتا اور ظاہر ہے کہ ایسی صورت
میں ان کے غلط ثات ہونے سے ہرگز کوئی اعتراض مذہب پر وارد نہیں ہوسکتا.دوسرے
یہ کہ پیدائش عالم کے متعلق بعض خیالات ایسے بھی ہیں جو بعد کی دست برد سے یا بعض
صورتوں میں غیر زبانوں میں تراجم کی غلطی کی وجہ سے مذہبی کتب کا حصہ بن گئے ہیں مگر
در حقیقت اصل الہامی کتب میں وہ پائے نہیں جاتے تھے.اور ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ ایسی
صورت میں بھی مذہب کی تعلیم پر حقیقتاً کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا.اور تیسرے یہ کہ
ان خیالات میں سے بعض واقعی اصل الہامی کتب میں پائے جاتے ہیں مگر ان کا
مطلب سمجھنے میں اکثر لوگوں نے غلطی کھائی ہے اور اس غلط تشریح کی وجہ سے جدید
محققین کو اعتراض کا موقعہ مل گیا ہے.مثلاً قرآن شریف میں یہ واقعی بیان ہوا ہے کہ خدا نے زمین و آسمان کو چھ ایام
میں پیدا کیا ہے.لیکن بعض لوگوں نے اس کے معنے کرنے میں یہ غلطی کھائی ہے کہ ایام
سے یہ چوبیس گھنٹے والے دن مراد لے لئے ہیں حالانکہ یوم کا لفظ عربی زبان میں
جہاں دن کے معنوں میں آتا ہے وہاں بہت دفعہ اس کے معنے صرف وقت اور زمانے
90
Page 91
کے بھی ہوتے ہیں اور جاہلیت کے عرب شعراء میں کثرت کے ساتھ یوم کا لفظ اسی
مفہوم میں استعمال ہوا ہے لیکن بعض لوگوں نے سادگی یا کم علمی سے اس کے معنے چھ دن
کر دیئے.اور پھر آگے سمجھنے والوں نے دن سے چوبیس گھنٹے مراد لے لئے حالانکہ خود
آیت کا قرینہ اس بات کو ظاہر کر رہا ہے کہ یہاں معروف دن مراد نہیں ہے کیونکہ یہ
معروف دن تو سورج کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور زمین کے چکر کے نتیجہ میں قائم ہوتا
ہے.مگر جس زمانہ کا اس آیت میں ذکر ہے وہ سورج اور زمین کے وجود سے پہلے کا
ہے.کیونکہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے زمین و آسمان اور سورج اور چاند اور ستاروں کو
چھ دنوں میں پیدا کیا ہے.پس لامحالہ یہاں دن سے مراد وہ دن لیا جائے گا جو ان تمسی
دنوں سے پہلے موجود تھا اور وہ عام زمانہ اور وقت ہے.پس نہ صرف لغت عرب بلکہ خود
آیت کا قرینہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہاں یوم سے مراد عام عرفی دن نہیں ہے بلکہ
زمانہ اور وقت مراد ہے.اور اس طرح آیت قرآنیہ کے یہ معنے ہوئے کہ ہم نے موجودہ
دنیا کو چھ مختلف اوقات میں درجہ بدرجہ پیدا کیا ہے.اور یہ وہ دعوی ہے جس کے متعلق
سائنس کی رُو سے کوئی اعتراض نہیں پڑتا بلکہ خود سائنسدان اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ
عالم آہستہ آہستہ مختلف درجوں اور دوروں سے گزر کر موجودہ حالت کو پہنچا ہے.اسی طرح مثلاً حدیث میں آتا ہے کہ دُنیا کی عمر سات ہزار سال کی ہے اور یہ کہ
آدم کو آنحضرت ﷺ سے پانچ ہزار سال پہلے پیدا کیا گیا تھا.اور اس کے معنے بعض
لوگوں نے غلطی سے یہ سمجھ لئے ہیں کہ گویا نسلِ انسانی کا آغاز صرف چند ہزار سال سے
ہوا ہے اور اس طرح مسئلہ ارتقاء والوں کو اعتراض کا موقعہ مل گیا ہے.حالانکہ حق یہ ہے
کہ اسلام ہرگز یہ تعلیم نہیں دیتا کہ یہ کارخانہ عالم صرف چند ہزار سال سے جاری ہے اور
اس سے پہلے کچھ نہیں تھا اور اسلام کی طرف اس خیال کو منسوب کرنا سراسر جہالت اور
نادانی ہے.اسلام کا تو یہ عقیدہ ہے کہ خدا تعالے کی کوئی صفت بھی کسی زمانہ میں مستقل
91
Page 92
طور پر معطل نہیں ہوتی اور ہر زمانہ میں اس کی ہر صفت کسی نہ کسی رنگ میں ظاہر ہوتی
رہتی ہے.پس چونکہ خلق کرنا بھی اس کی صفات میں سے ایک صفت ہے لہذا یہ عقیدہ
سراسر اسلام کے خلاف ہوگا اگر یہ سمجھا جائے کہ گویا صرف پانچ یا چھ یا سات ہزارسال
سے ہی مخلوقات کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور اس سے پہلے کچھ نہیں تھا.اس سے ثابت ہوا
کہ حدیث مذکورہ بالا کے یہ معنے نہیں ہو سکتے کہ دُنیا کی عمر صرف چند ہزار سال کی ہے.بلکہ جیسا کہ خود اکا بر اسلام نے لکھا ہے اور موجودہ زمانہ کے مامور وصلح حضرت
مسیح موعود علیہ السلام بافی سلسلہ احمدیہ نے مفصل تشریح فرمائی ہے.اس حدیث کے یہ معنے ہیں کہ دنیا پر مختلف دور آتے رہے ہیں اور موجود نسل کا
دور چند ہزار سال سے شروع ہے اور نمعلوم ایسے کتنے دور اس دنیا پر آئے ہیں.چنانچہ
اسلام کے ایک مشہور عالم اور صوفی حضرت محی الدین ابن عربی ” لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ
مجھے عالم کشف میں دکھایا گیا کہ اس دُنیا میں لاکھوں آدم گذرے ہیں اور جب ایک
آدم کی نسل کا دور ختم ہوتا ہے تو دوسرے آدم کا دور شروع ہو جاتا ہے اور اس بات کا علم
خدا کے پاس ہے کہ دُنیا پر کتنے دور آئے ہیں.پس اس معنے کے لحاظ سے قطعاً کوئی
اعتراض نہیں رہتا اور یہی معنے درست ہیں اور یہ خیال اسلام کی رو سے سراسر باطل ہے
کہ آج سے چند ہزار سال قبل کوئی مخلوق نہیں تھی اور گویا خد انعوذ باللہ معطل بیٹھا تھا.اسی طرح قرآن شریف میں آتا ہے کہ ہم نے آدم کو مٹی سے بنا کر پھر اپنے حکم
سے اُس کے اندر جان ڈالی.اور اس سے بعض لوگوں نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ گویا
نسلِ انسانی کا آغاز اس طرح پر ہوا ہے کہ خُدا نے ایک مٹی کا بت بنایا اور پھر اس میں
پھونک مار کر جان ڈال دی اور اس کے بعد نسلِ انسانی کا سلسلہ شروع ہو گیا.حالانکہ
الحکم 30 مئی 1908 ء و چشمہ معرفت صفحہ 160
فتوحاتِ مکيه باب حدوث الدنيا جلد 3
92
Page 93
آیت قرانی کا صرف اتنا مطلب ہے کہ آدم کی خلقت میں اجزائے ارضی کا خمیر ہے
جس کی وجہ سے وہ مادیات کی طرف جلد مائل ہو جاتا ہے اور اسی لئے خدا نے اُس کی
بناوٹ میں رُوحانی عنصر کا چھینٹا دے دیا ہے تا کہ اس کے مادی عناصر اُس کی
روحانی ترقی میں روک نہ ہو جائیں.گویا ایک نہایت لطیف مضمون کو جسے قرآن شریف
نے حسب عادت استعارہ کے رنگ میں ادا کیا تھا مادی معنوں میں لے کر اعتراض کا
نشانہ بنالیا گیا ہے.مگر میں کہتا ہوں کہ اگر اس آیت کے ظاہری معینے لئے جاویں تو پھر
بھی کوئی اعتراض نہیں پڑسکتا کیونکہ قرآن شریف پیدائش عالم کی تفصیلی ماہیت بیان
کرنے کے لئے نازل نہیں ہوا بلکہ اس کا کام دنیا کی اخلاقی اور روحانی اصلاح ہے اور
اس نے دوسرے مضامین کا صرف اس حد تک ذکر کیا ہے جس حد تک کہ اس کی اس
غرض کے لئے ضروری تھا اور باقی باتوں کو چھوڑ دیا ہے.مثلاً قوانین طب کا بیان کرنا
قرآن شریف کا کام نہیں کیونکہ قرآن شریف طب کی کتاب نہیں ہے لیکن چونکہ انسان
کی صحت عامہ کا اس کے اخلاق اور دین پر اثر پڑتا ہے اس لئے کہیں کہیں ضروری سمجھ کر
شریعت اسلامی نے ایسی اصولی باتوں کی طرف بھی توجہ دلا دی ہے جو حفظانِ صحت کے
ساتھ تعلق رکھتی ہیں.لیکن صرف اُسی حد تک اپنے بیان کو محدود رکھا ہے جہاں تک کہ
اُس کی اپنی غرض و غایت کے ماتحت ضروری تھا.اس اصول کے ماتحت اگر مذکورہ بالا
قرآنی آیت کے معنے کئے جائیں تو کوئی اعتراض نہیں رہتا.قرآن صرف یہ کہتا ہے کہ
خدا نے آدم کو آواز دینے والی تیار شدہ مٹی سے پیدا کیا اور پھر اُس کے اندر اپنے حکم سے
جان ڈالی.جس کا یہ مطلب ہے کہ انسان ایک حیوانِ ناطق ہے جو دوسرے حیوانوں
سے ممتاز طور پر صفت نطق کے ذریعہ ترقی کرنے کے لئے پیدا کیا گیا ہے اور دوسرے یہ
کہ اس کا جسم اور اُس کی روح دونوں خدا کی مخلوق ہیں جو ایک خاص طریق عمل کے
ل سورة الحجر - آیت 34
93
Page 94
مطابق عالم وجود میں آئے ہیں، لیکن اس بات کے متعلق قرآن شریف خاموش ہے کہ
مٹی سے کونسی مٹی مراد ہے کیونکہ سارے کیمیاوی سالٹ مٹی ہی کا حصہ ہیں.اور پھر اس
بات کے متعلق بھی خاموش ہے کہ خدا نے انسان کو مٹی سے کس طرح بنایا ، کتنے عرصہ
میں بنایا ، کتنے درجوں اور کس قسم کے درجوں میں سے گذار کر موجودہ حالت کو پہنچایا
وغیر ذالک.اسی طرح خدا نے اس کے اندر جان ڈالی تو کہاں سے ڈالی ،کس طرح
ڈالی ، کتنے درجوں اور کس قسم کے درجوں میں ڈالی اور اس کا نشو ونما کیسے کیا؟ ان
سوالات کی تفصیل بیان کرنا قرآن شریف نے اپنی غرض وغایت سے لاتعلق سمجھا اس
لئے خاموشی اختیار کی.پس کوئی سائنسدان قرآن شریف کے بیان پر اعتراض نہیں کر
سکتا کیونکہ اس میں خلقِ انسان کی ایک ایسی اجمالی اور صحیح کیفیت بیان کی گئی ہے جو
سائنس کی کسی ثابت شدہ حقیقت کے خلاف نہیں بلکہ خود سائنس کے لئے ایک اصولی
شمع ہدایت کا کام دیتی ہے.اور اگر کوئی شخص قرآن شریف کے اس بیان پر اپنی طرف
سے حاشیے چڑھا کر پھر اُسے سائنس کے کسی مسئلہ کے مقابل پر لاتا ہے تو اُس کا ذمہ وار
وہ خود ہے اسلام پر اس کی وجہ سے کوئی حرف گیری نہیں کی جاسکتی.اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ حضرت حوا کو حضرت آدم کی پہلی سے پیدا کیا
گیا.مگر بعض لوگوں نے اس کے یہ معنے سمجھ لئے کہ آدم کے جسم کو پھاڑ کر اس کی پسلی کی
ہڈی سے تو ا کا وجود پیدا کیا گیا.اور اس طرح سائنس والوں کو اعتراض کرنے کا موقعہ
مل گیا ہے حالانکہ جیسا کہ الہامی کتب کا عام طریق ہے یہ الفاظ استعارے کے طور پر
استعمال ہوئے ہیں اور اس حدیث کے معنے یہ ہیں کہ عورت مرد کے پہلو بہ پہلو ر ہنے
کے لئے پیدا کی گئی ہے اور وہ مرد کی زندگی کا لازمی حصہ اور اس کی رفیق حیات ہے.لیکن مرد کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ جس طرح پسلی کی ہڈی ٹیڑھی ہوتی ہے عورت میں بعض
مصالح کے ماتحت بعض فطری کمزوریاں رکھی گئی ہیں اور مرد کو اس کے ساتھ معاملہ کرنے
94
Page 95
میں اُس کی فطری کمزوریوں کا خیال رکھتے ہوئے ملاطفت اور عفو کا طریق اختیار کرنا
چاہئے.چنانچہ دوسری جگہ حدیث میں آنحضرت ﷺ نے عورت کے متعلق یہی
الفاظ استعمال فرمائے ہیں کہ عورت ایک ٹیڑھی پسلی کی طرح ہے اور یہی ٹیڑھا پن
جنس نسوانی کا حسن ہے.پس مردوں کو چاہئے کہ عورت کی اس فطری بھی کا خیال رکھیں
اور اس کو اس قدر سیدھا کرنے کی کوشش نہ کریں کہ وہ ٹوٹ ہی جائے اور اپنے جنسی
حسن کو کھو بیٹھے.الغرض قرآن شریف یا صحیح احادیث میں جو پیدائش عالم یا پیدائش آدم کے
متعلق الفاظ استعمال کئے گئے ان پر غور کرنے سے پتہ لگتا ہے کہ ان کے متعلق ہر گز کسی
قسم کا اعتراض نہیں ہو سکتا.اور جن لوگوں نے اعتراض کیا ہے یا ان کو قابل اعتراض سمجھا
ہے وہ ان لوگوں کی اپنی ناواقفیت یا کم علمی ہے.اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ دوسری
الہامی کتب کی جو تعلیمات قابل اعتراض مجھی گئی ہیں اُن میں سے بھی اکثر کے متعلق
غلط فہمی پیدا ہوئی ہے اور ان کے صحیح معنوں کو سمجھا نہیں گیا اور اگر کسی جگہ کوئی اعتراض پیدا
بھی ہوتا ہے تو وہ یقیناً بعد کی دست بُرد کا نتیجہ ہے جس سے بد قسمتی سے سوائے
قرآن شریف کے کوئی الہامی کتاب نہیں بچی.ہاں چونکہ خدا کے فضل سے قرآن مجید ہر
طرح محفوظ ہے اور سخت سے سخت مخالف بھی اس کے متعلق شہادت دیتے ہیں کہ وہ
تحریف سے بالکل پاک رہا ہے اس لئے ہم قرآن شریف کے متعلق یہ بات دعوئی کے
ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی کوئی بات ایسی نہیں کہ جس پر کوئی معقول اعتراض ہو سکتا ہو.اور سائنس کی کوئی صداقت قرآن شریف کی کسی تعلیم کے خلاف نہیں اور ایسا ہونا بھی
ناممکن ہے کیونکہ قرآن شریف خدا کا قول ہے اور نیچر جس کی مفسر سائنس ہے خدا کا فعل
ہے اور خد کا اقول اور فعل آپس میں ٹکر انہیں سکتے.اس بحث کے ختم کرنے سے قبل ڈارون کے رسوائے عالم نظریہ کے متعلق
95
Page 96
خصوصیت سے یہ بتا دینا بھی ضروری ہے کہ ابھی تک یہ نظریہ صرف ایک قیاس یعنی
تھیوری کی حد تک ہے اور سائنس کے ثابت شدہ حقائق میں داخل نہیں بلکہ بہت سے
سائنسدانوں نے اسے سختی کے ساتھ رڈ کیا ہے.چنانچہ دنیا کے مشہور سائنسدان سرجان
امبروز فلیمنگ کی وفات پر جو تار اخباروں میں چھپی تھی اس میں لکھا تھا کہ :
گوسر جان ایک نہایت نامور سائنسدان تھا مگر وہ معجزات کا منکر نہیں تھا..اور ڈارون کی ارتقائی تھیوری کو ایک محض دماغی تخیل خیال کرتا تھا.پس اس مسئلہ کی بنا پر خدا کی ذات کے متعلق اعتراض کرنا ہر گز دانائی کا رستہ نہیں
سمجھا جا سکتا.خدا غیر مخلوق ہے
انگلی دلیل شروع کرنے سے پہلے ایک شبہ کا ازالہ ضروری ہے جو اس موقعہ پر
بعض نا واقف لوگوں خصوصاً نوجوانوں کے دلوں میں پیدا ہو ا کرتا ہے.اور وہ یہ ہے کہ
اگر اس دُنیا کو خُدا نے پیدا کیا ہے تو خدا کوکس نے پیدا کیا ہے؟ یعنی جب دُنیا کے متعلق
یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کا خالق و مالک کون ہے تو خدا کے متعلق بھی یہ سوال پیدا ہونا
چاہئے کہ خدا کا خالق و مالک کون ہے؟ اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ قطع نظر اس کے کہ خدا
نے متعلق ایسا سوال پیدا ہی نہیں ہو سکتا جیسا کہ آگے چل کر ثابت کیا جائے گا اگر یہ فرض
بھی کر لیا جائے کہ جو ہستی اس دُنیا کی خالق و مالک ہے اُسے کسی اور بالا ہستی نے پیدا کیا
ہے تو پھر بھی دلیل کی رو سے کوئی حرج لازم نہیں آتا کیونکہ اس صورت میں ہم اس
بالا ہستی ہی کا نام خدا رکھیں گے اور اس ماتحت ہستی کو مخلوقات میں سے ایک مخلوق اور
سلسلہ اسباب میں سے ایک سبب اور وسائط خلق میں سے ایک واسطہ قرار دینگے.اور
سول اینڈ ملٹری گزٹ لاہور.مؤرخہ 22 اپریل 1945 ء
96
Page 97
اگر کوئی شخص یہ سوال کرے کہ پھر اس بالا ہستی کا خالق و مالک کون ہے؟ تو اس کا جواب
یہ ہوگا کہ اگر یہ بالا ہستی بھی کسی بالا در بالا ہستی کی مخلوق ہے تو پھر یہ بالا در بالا ہستی ہی خدا
کہلائے گی اور اس کے نیچے کی تمام ہستیاں مخلوقات کا حصہ سمجھی جائینگی.الغرض جس
ہستی پر بھی اس سلسلہ کو بند قرار دیا جائے یعنی جس ہستی کو بھی اس سلسلہ کی ابتدائی ہستی
سمجھا جائے جس کے اوپر کوئی اور ہستی نہیں ہے اُسی کا نام ہم خُدا رکھتے ہیں اور اس کے
سوا باقی سب کو مخلوقات کا حصہ قرار دیتے ہیں.اور اگر کسی شخص کو یہ خیال گذرے کہ چونکہ ہر ہستی کے متعلق یہ سوال پیدا ہوتا
جائے گا کہ اس کا خالق و مالک کون ہے اس لئے کوئی ایسی ہستی ثابت ہی نہ ہو سکے گی
جسے ابتدائی ہستی کہا جاسکے.تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات عقلاً ناممکن ہے کہ اس
سلسلہ کی کوئی ابتدائی ہستی نہ ہو کیونکہ اگر کوئی ابتدائی نہستی تسلیم نہ کی جائے تو اس کا لازمی
نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نیچے کی تمام ہستیوں کے وجود سے جو ابتدائی ہستی کا نتیجہ ہیں اور جن
میں سے ایک دُنیا بھی ہے انکار کرنا پڑتا ہے.جس کے دوسرے الفاظ میں یہ معنی ہیں کہ
دُنیا و مافیہا صرف وہم ہی وہم ہے ورنہ در اصل نہ کوئی زمین ہے اور نہ کوئی آسمان ہے اور
نہ کوئی چاند ہے اور نہ کوئی سورج ہے اور نہ کوئی ستارے ہیں اور نہ کوئی انسان ہے اور نہ
کوئی حیوان ہے اور نہ کوئی درخت ہے اور نہ کوئی پانی ہے اور نہ کوئی ہوا ہے اور نہ کوئی اور
چیز ہے.مثلاً اگر ہم اس دُنیا کو الف قرار دیں اور اس کے خالق کا نام ب رکھیں اور یہ
فرض کریں کہ ب کو ج نے پیدا کیا اور ج کو د نے.اور اسی طرح جہاں تک
ہماری طاقت ہے اس سلسلہ کو اوپر لے جاتے چلے جائیں یعنی ہر ہستی کے متعلق یہ فرض
کرتے جائیں کہ وہ کسی دوسری بالا ہستی کی مخلوق ہے تو ظاہر ہے کہ یہ سلسلہ کسی جگہ بھی
ختم نہیں ہوگا.جس کے یہ معنے ہیں کہ اس سلسلہ کی کوئی ایسی کڑی ثابت نہیں ہو سکے گی
جسے ہم ابتدائی کڑی کہ سکیں اور جب ابتدائی کڑی ثابت نہ ہوئی تو لامحالہ اس سے نیچے
97
Page 98
والی کڑی بھی جو اس ابتدائی کڑی کی مخلوق ہے ثابت نہ ہوگی اور جب یہ نیچے والی کڑی
ثابت نہ ہوئی تو اُس نیچے والی کڑی سے نیچے کی کڑی بھی ثابت نہ ہوگی.الغرض ابتدائی
کڑی کے ثابت نہ ہو سکنے کی وجہ سے نیچے کی تمام کڑپاں باطل چلی جاتی ہیں.گویا او پر
والی مثال لے کر کہہ سکتے ہیں کہ اگر د کا وجود ثابت نہیں ہے تو لا محالہ ج بھی ثابت
نہیں ہے.اور اگر ج نہیں ہے تو ب بھی نہیں اور اگر ب نہیں تو الف بھی نہیں.گویا د کے وجود کے انکار سے الف کا انکار لازم آتا ہے حالانکہ کم از کم الف کا وجود
جو ہم نے اس دُنیا کا نام رکھا ہے ) مسلمہ طور پر ثابت ہے کیونکہ دُنیا کے موجود ہونے
سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا.پس ثابت ہوا کہ ایسا طریق استدلال جس کا نتیجہ یہ نکلے
کہ اس سلسلہ کی کوئی ابتدائی کڑی ثابت نہ ہو سکے غلط ہے کیونکہ اس سے دُنیا کے موجود
ہونے سے انکار کرنا پڑتا ہے.لہذا ہم مجبور ہیں کہ اس سلسلہ کی کوئی ابتدائی کڑی قرار
دیں جس کے یہ معنے ہیں کہ ہم کسی ایسی ہستی پر ایمان لائیں جس کے اوپر کوئی اور ہستی
نہیں ہے اور ظاہر ہے کہ ایسی ہستی وہی ہو سکتی ہے جو غیر مخلوق ہو اور اسی کا نام ہم خدا
رکھتے ہیں.خلاصہ کلام یہ کہ اس سلسلہ کو واہ کتنا بھی لمبا کھینچا جائے کسی نہ کسی جگہ اسے
بند قرار دینا ہوگا.یعنی کسی نہ کسی ہستی سے اس سلسلہ کی ابتداء تسلیم کرنی پڑیگی اور یہی
ابتدائی ہستی خدا ہے جو غیر مخلوق ہے اور اس کے ماتحت جتنی بھی ہستیاں ہیں خواہ وہ ایک
دوسرے سے اپنے طبعی قومی اور فطری طاقتوں میں کیسی ہی اعلیٰ اور اشرف ہوں سب کی
سب بلا استثناء مخلوقات کا حصہ اور خدائے واحد کے قبضہ تصرف کے نیچے ہیں.وهو المراد
اس کے بعد میں مختصر طور پر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دراصل یہ سوال ہی غلط ہے کہ
خُدا کا خالق و مالک کون ہے.کیونکہ خُدا کے متعلق ایسا سوال پیدا ہی نہیں ہوسکتا.بات
یہ ہے کہ خدائیت اور مخلوقیت کا مفہوم ایک دوسرے کے بالکل منافی واقع ہوئے ہیں اور
98
Page 99
یہ بات عقلاً ناممکن ہے کہ یہ دونوں مفہوم ایک وجود میں جمع ہوں کیونکہ جہاں خدائیت کا
مفہوم اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ صرف اس ہستی کا نام خدا رکھا جائے جو سب سے
بالا ہے وہاں مخلوقیت کا مفہوم اس بات کا متقاضی ہے کہ جس ہستی کو ہم مخلوق قرار دیں
اس کے اوپر کوئی اور ہستی بھی ہو.پس یہ دونوں مفہوم کسی صورت میں بھی ایک جگہ جمع
نہیں ہو سکتے.خوب سوچ لو کہ کسی ہستی کو مخلوق قرار دینے کے یہ معنی ہیں کہ ہم اُس ہستی
کے اوپر ایک اور بالا ہستی کے وجود کو تسلیم کریں جو اس کی خالق و مالک ہے.پس اگر خدا
کو مخلوق سمجھا جائے تو اس سے یہ لازم آئے گا کہ خُدا کے اوپر بھی ایک اور ہستی موجود
ہے جو خدا کی خالق ہے، خدا کی مالک ہے، خدا پر حکمران ہے اور جس کے سہارے پر خدا
کی ذات قائم ہے غرض جو ہر طرح اور ہر جہت سے خُدا سے بالا اور فائق ہے.اب غور
کردو کہ اگر واقعی کوئی ایسی بالا ہستی موجود ہے تو پھر وہی بالا ہستی ہی خدا ہوئی نہ کہ یہ
نام نہاد ماتحت خدا ، جو مخلوق بھی ہے اور مملوک بھی ہے اور محکوم بھی ہے.کون عقلمند ہے جو
اس بالا ہستی کے موجود ہوتے ہوئے اس ماتحت ہستی کے متعلق خُدا کا لفظ استعمال کر سکتا
ہے؟ ہاں پھر سوچو اور غور کرو کہ تم صرف اس وقت تک کسی ہستی کا نام خدا رکھ سکتے ہو
جب تک کہ تم اسے غیر مخلوق سمجھتے ہو اور جو نہی کہ تم اس کے متعلق مخلوق ہونے کا سوال
پیدا کرو تم مجبور ہو جاتے ہو کہ اس کے اوپر ایک بالا ہستی کے وجود کو تسلیم کرو جو اس کی
خالق و مالک ہے.اور اس بالا ہستی کو تسلیم کرتے ہی خدائیت کا مفہوم اس ماتحت ہستی
سے خارج ہو کر فوراً اُس بالا ہستی کی طرف منتقل ہو جاتا ہے.الغرض جس ہستی کو بھی
مخلوق قرار دیا جائے وہ خدا نہیں رہ سکتی کیونکہ اس صورت میں خدا اس ہستی کا نام رکھا
جائے گا جو اس کی خالق اور اُس پر فائق ہے.پس ثابت ہوا کہ خدائیت اور مخلوقیت کے
مفہوم کبھی بھی ایک وجود میں جمع نہیں ہو سکتے.یعنی یہ ناممکن ہے کہ ایک ہستی خدا بھی ہو
اور مخلوق بھی.اور جب یہ ناممکن ہو ا تو ہمیں یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ جب ہم کسی ہستی کو
99
Page 100
خدامان لیں تو پھر اس کے متعلق یہ سوال پیدا ہی نہیں ہوسکتا کہ اس کا خالق کون ہے.تیسرا جواب جو میں اس طبہ کا دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ قطع نظر اس بات کے
کہ خُدا کے متعلق یہ سوال اُٹھایا ہی نہیں جاسکتا کہ اسے کس نے پیدا کیا ہے آؤ ہم تھوڑی
دیر کے لئے یہ فرض کر لیتے ہیں کہ خُدا مخلوق ہے اور پھر دیکھتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا
ہے.ظاہر ہے کہ ہر ایک چیز اپنے اندر بعض مخصوص صفات اور خواص رکھتی ہے اور انہی
خواص اور صفات کی وجہ سے وہ دوسری چیزوں سے ممتاز نظر آتی ہے.مثلاً پانی اپنے
اندر ایسے خواص رکھتا ہے جو ہوا اور پتھر میں نہیں پائے جاتے اور انہی خواص کی وجہ سے
ہم ہوا اور پتھر سے پانی کا امتیاز کرتے ہیں.اگر ان خواص کو پانی سے الگ کر لیا جائے تو
پھر پانی پانی نہیں رہ سکتا.خلاصہ کلام یہ کہ ہر اک چیز اپنے اندر بعض مخصوص صفات اور
خواص رکھتی ہے اور یہی خواص اور صفات ہیں جو اس کی ہستی کو قائم رکھنے والے اور
دوسری چیزوں سے اس کے امتیاز کا موجب ہوتے ہیں.اب جب ہم ایک ہستی کے
متعلق خدا کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ہماری عقل اس کے لئے بعض ایسی صفات تجویز
کرتی ہے کہ جن کی وجہ سے یہ ہستی خدا کا نام پانے کی حقدار ہوتی اور دوسری چیزوں
سے الگ اور ممتاز نظر آتی ہے.گویا یہ صفات خدائیت کے لئے بطورستون کے ہیں جن
کو اگر اس سے الگ کر لیا جائے تو پھر وہ خدا نہیں رہ سکتا.مثلا عقل ہمیں بتاتی ہے کہ اگر
کوئی خدا ہے تو وہ قدیم ہونا چاہیے یعنی وہ ہمیشہ سے موجود ہونا چاہئے.عقل ہمیں بتاتی
ہے کہ اگر کوئی خدا ہے تو وہ غیر فانی ہونا چاہئے یعنی وہ ہمیشہ رہنا چاہئے.عقل ہمیں بتاتی
ہے کہ اگر کوئی خدا ہے تو وہ قائم بالذات ہونا چاہئے یعنی وہ بغیر کسی دوسری ہستی کے
سہارے کے خود اپنی ذات میں قائم ہونا چاہئے.عقل ہمیں بتاتی ہے کہ اگر کوئی خدا ہے
تو وہ قادر مطلق ہونا چاہئے یعنی اس کی قدرت کامل ہونی چاہئے اور اس کے کاموں میں
کسی کو دخل انداز ہونے کی طاقت نہ ہونی چاہئے.عقل نہیں بتاتی ہے کہ اگر کوئی خدا
100
Page 101
ہے تو وہ احد ہونا چاہئے یعنی وہ واحد و یکتا ہونا چاہئے اور اس کے مقابل میں کوئی ایسی
ہستی موجود نہ ہونی چاہئے جو اس کی ہمسری کا دعوی کر سکے.عقل ہمیں بتاتی ہے کہ اگر
کوئی خدا ہے تو وہ اپنی تمام صفات میں مستقل اور آزاد ہونا چاہئے یعنی اُس کی تمام
صفات اس کے اندر بالاستقلال پائی جانی چاہئیں اور ایسا نہیں ہونا چاہئے کہ اس کی
صفات کا قیام کسی دوسری ہستی کی مرضی پر موقوف ہو.یہ چند صفات جو میں نے بطور مثال کے بیان کی ہیں ایسی صفات ہیں جو عقل کی
رو سے اس ہستی میں پائی جانی ضروری ہیں جس کا نام ہم خدار کھتے ہیں کیونکہ نظام عالم کا
قیام جس طرح کہ وہ چلتا چلا آیا ہے اور چل رہا ہے بغیر ان صفات کے محال ہے.گویا یہ
صفات اور اسی قسم کی دوسری صفات عرشِ الوہیت کے لئے بطورستون کے ہیں جن کے
بغیر یہ عرش کسی صورت میں قائم نہیں رہ سکتا.لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اگر خدا کو مخلوق ما نہیں
تو اس کی ان تمام صفات سے انکار کرنا پڑتا ہے اور ان صفات میں سے کوئی ایک صفت
بھی ایسی نہیں جو خدا کو مخلوق مان کر اُس میں قائم رہ سکے.مثلاً یہ ظاہر ہے کہ اگر خدا مخلوق
ہے تو وہ قدیم نہیں ہوسکتا بلکہ اسے حادث ماننا پڑیگا.اگر خدا مخلوق ہے تو وہ غیر فانی نہیں
رہ سکتا بلکہ اُسے فانی ماننا پڑیگا.اگر خدا مخلوق ہے تو وہ قائم بالذات نہیں رہ سکتا بلکہ اُسے
اس ہستی کے سہارے پر قائم مانا پڑیگا جو اس کی خالق و مالک ہے.اگر خدا مخلوق ہے تو وہ
قادر مطلق نہیں رہ سکتا بلکہ اس کی قدرتوں کو محدود ماننا پڑیگا اور نیز اس بات کو تسلیم کرنا
پڑیگا کہ وہ ہستی جو اس کی خالق و مالک ہے وہ جب اور جس طرح چاہے اس کے کاموں
میں دخل انداز ہوسکتی ہے.اگر خدا مخلوق ہے تو وہ احد نہیں مانا جاسکتا بلکہ اس بات کا
امکان ماننا پڑیگا کہ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے خدا ہیں کیونکہ جو ہستی ایک خدا پیدا کر
سکتی ہے کوئی وجہ نہیں کہ اس نے اپنی صفت خلق اور اقتدار وحکومت کی وسعت ثابت
کرنے کے لئے بہت سے خدا نہ پیدا کئے ہوں.اگر خدا مخلوق ہے تو وہ اپنی کسی صفت
101
Page 102
میں بھی مستقل اور آزاد نہیں سمجھا جاسکتا بلکہ اس کی ہر صفت اس بالا ہستی کی مرضی اور رحیم
پر موقوف مانی جائے گی جس نے خدا کو پیدا کیا ہے کیونکہ مخلوق کی ہر صفت بھی مخلوق ہوتی
ہے اور خالق کے قبضہ تصرف کے نیچے ماننی پڑتی ہے.الغرض خدا کو مخلوق ماننے کا یہ
نتیجہ ہوتا ہے کہ خدا کی تمام وہ صفات جن پر عقل کی رُو سے عرشِ الوہیت کا قیام تسلیم کرنا
پڑتا ہے باطل چلی جاتی ہیں اور خدا اپنی خدائیت کے تخت سے معزول ہو کر ان معمولی
مخلوق ہستیوں کی صف میں آکھڑا ہوتا ہے جو اپنی ہر بات میں اپنے خالق و مالک کا
سہارا ڈھونڈتی ہیں اور قطعاً کوئی آزادانہ زندگی نہیں رکھتیں.خلاصہ کلام یہ کہ خواہ کسی
جہت سے بھی دیکھا جائے خدائیت اور مخلوقیت کا مفہوم ایسی طرح ایک دوسرے کے
مقابل اور ضد میں واقع ہوا ہے کہ کسی طرح بھی ایک وجود میں جمع نہیں ہوسکتا.پس ہم
مجبور ہیں کہ جس ہستی کو ہم خدا قرار دیں اُسے غیر مخلوق سمجھیں اور جسے مخلوق سمجھیں اس کا
نام خدا نہ رکھیں.وھوالمراد.کیوں نہ اس دُنیا کو ہی غیر مخلوق سمجھ لیا جائے؟
اس کے بعد میں ایک اور شبہ کا جواب دینا چاہتا ہوں جو اکثر لوگوں کے دلوں
میں پیدا ہوسکتا ہے اور جو یورپ کے دہریوں کی طرف سے عموماً پیش کیا جاتا ہے.اور وہ
یہ کہ اگر ہم نے خدا کو غیر مخلوق قرار دیکر اُسے خود بخود ہمیشہ سے بغیر کسی خالق و مالک کے
ماننا ہے تو کیوں نہ اس دنیا کو ہی قائم بالذات اور غیر مخلوق قرار دے لیا جائے تا کہ اس
ساری بحث کا یہیں نیچے ہی خاتمہ ہو جائے.یہ وہ شبہ ہے جو اس جگہ پیدا ہوسکتا ہے اور
جو واقعی اکثر لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوا کرتا ہے اور دہریوں کی طرف سے بھی عموماً
یہی شبہ پیش کیا جاتا ہے.لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ شبہ
سراسر قلت مدیر پر مبنی اور محض عامیانہ تخیل کا نتیجہ ہے اور اس سے زیادہ اس کی کوئی
102
Page 103
حیثیت نہیں.دراصل اس شبہ کی بنا اس خیال پر ہے کہ چونکہ خدا کو غیر مخلوق مانا جاتا ہے
اس لئے ثابت ہوا کہ کسی چیز کا خود بخود اپنے آپ سے بغیر کسی خالق کے ہونا بھی ممکن
ہے.اور جب یہ بات ثابت ہوگئی تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم اس دنیا کو مخلوق قرار دیکر اس
کے اوپر کسی خدا کے وجود پر ایمان لائیں بلکہ ہم اس دنیا کو ہی غیر مخلوق اور قائم بالذات
قرار دیکر اس قصہ کو یہیں ختم کر دیتے ہیں.اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ ہم نے جو دنیا کو
مخلوق مانا ہے تو اس بنا پر نہیں کہ چونکہ ہر چیز کا مخلوق ہونا ضروری ہے اس لئے دُنیا بھی
مخلوق ہونی چاہئے بلکہ اس لئے کہ دُنیا کے حالات اُسے مخلوق ثابت کر رہے ہیں.اگر
ہم یہ اصول قائم کرتے کہ بلا استثناء ہر ایک چیز کا مخلوق ہونا ضروری ہے خواہ اس کے
حالات کیسے ہی ہوں تو پھر بیشک یہ اعتراض ہوسکتا تھا کہ یا تو خدا کو بھی مخلوق مانا جائے
اور یا پھر اس اصول کر رڈ کر کے دُنیا کے غیر مخلوق ہونے کے امکان کو تسلیم کیا جائے.پس یہ اعتراض غلط ہے کہ چونکہ خدا کو غیر مخلوق ماننا پڑتا ہے اس لئے کوئی حرج نہیں کہ
دُنیا کو ہی غیر مخلوق سمجھ لیا جائے.ہر اک چیز اپنے اپنے مخصوص حالات رکھتی ہے اور انہی
مخصوص حالات کے ماتحت اس کے متعلق کوئی رائے قائم کی جاسکتی ہے.پانی کے
حالات الگ ہیں اور آگ اور پتھر اور ہو ا کے الگ.اور یہ ہماری نادانی ہوگی کہ ہم ان
سب کو ایک ہی قانون کے ماتحت سمجھ کر ایک ہی معیار سے ناپنے لگ جائیں.اسی
طرح دنیا کی چیزوں کے معیار کے مطابق خدا کے متعلق اور خدا کے معیار کے مطابق
دنیا کے متعلق رائے نہیں لگائی جاسکتی بلکہ ہر ایک کو اس کے مخصوص حالات کے مطابق
الگ الگ معیار سے پرکھا جائے گا.اب اس اصل کے ماتحت ہم دیکھتے ہیں تو صاف نظر آتا ہے کہ خدا مخلوق نہیں مگر
دنیا ضرور مخلوق ہے.خدا کے متعلق تو ہم مندرجہ بالا بیان میں یہ ثابت کر چکے ہیں کہ وہ
مخلوق نہیں ہوسکتا کیونکہ اول تو اگر ہم خدا کو مخلوق ما نہیں یعنی اس کا کوئی خالق تسلیم کریں تو
103
Page 104
خدائیت کا مفہوم فوراً اُس سے نکل کر اُس کے خالق کی طرف منتقل ہو جاتا ہے یعنی مخلوق
کا مفہوم ذہن میں آتے ہی خدا خدا نہیں رہتا.دوسرے یہ کہ خدا کو مخلوق مان کر اس کی
تمام ان صفات کا انکار کرنا پڑتا ہے جو عقل کی رو سے عرشِ الوہیت کے لئے بطور سیتون
کے تسلیم کی جاتی ہیں اور جن کے بغیر خدا خدا نہیں رہ سکتا.الغرض خدا کے متعلق یہ قطعی
طور پر ثابت کیا جا چکا ہے کہ وہ مخلوق نہیں ہو سکتا.اب رہا دنیا کا سوال سو اس کے متعلق
بھی مفصل بحث او پر گذر چکی ہے کہ وہ خود اپنے حالات سے اپنے آپ کو مخلوق ثابت کر
رہی ہے.اگر اس کے حالات ایسے نہ ہوتے جن سے اس کا مخلوق ہونا ثابت ہوتا تو ہم
بڑی خوشی سے اسے غیر مخلوق مان لیتے لیکن جہاں خدا اپنے حالات سے اپنے آپ کو
غیر مخلوق منوارہا ہے وہاں یہ دُنیا زبان حال سے پکار پکار کر یہ شہادت دے رہی ہے کہ
میں کسی بالا ہستی کی قدرت خلق کا کرشمہ ہوں اور اُسی کے سہارے پر قائم ہوں.سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دُنیا کی کوئی چیز بھی ایسی نہیں کہ جسے اگر مخلوق مانا
جائے تو ہمیں اس کی کسی مخصوص صفت کا انکار کرنا پڑے بمقابلہ خدا کے کہ جسے مخلوق
مان کر اس کی تمام اصولی صفات کا انکار کرنا پڑتا ہے.کمامر.مثلاً اگر ہم پانی کو مخلوق
مانیں تو اس کا کوئی طبعی خاصہ ایسا نہیں جس کا ہمیں انکار کرنا پڑے.اگر آگ یا ہوا کو
مخلوق ما نہیں تو پھر بھی آگ اور ہوا کے تمام خواص برقرار رہتے ہیں.انسان کو مخلوق
ما نہیں تو اس کے انسان ہونے میں قطعاً کوئی حرج لازم نہیں آتا.زمین اور چاند اور
سورج کو مخلوق ما نہیں تو اُن میں سے کسی کی طبعی صفات میں رخنہ واقع نہیں ہوتا.اسی
طرح اگر دیگر عناصر کو مخلوق قرار دیں تو پھر بھی اُن کی ماہیت اسی طرح قائم رہتی ہے.غرضیکہ دُنیا کی کوئی چیز بھی خواہ وہ ادنی ہے یا اعلیٰ مرکب ہے یا مفرد ایسی نہیں ہے کہ
اسے مخلوق ماننے سے اس کی کسی بنیادی صفت کا بطلان لازم آئے بلکہ وہ مخلوق مانی جا کر
بھی اُسی طرح قائم و برقرار رہتی ہے جیسا کہ وہ اب عملاً دنیا میں موجود ہے.لیکن اگر
104
Page 105
خُدا کو مخلوق قرار دیں تو اس کی تمام وہ صفات باطل چلی جاتی ہیں جو اس کی خدائیت کے
لئے بطور ستون کے ہیں اور خدا خدا نہیں رہتا.پس یہ جہالت کا خیال ہے کہ چونکہ خدا کو
غیر مخلوق ماننا پڑتا ہے اس لئے کیا حرج ہے کہ دُنیا کو ہی غیر مخلوق سمجھ لیا جائے.دیکھو پانی
بوجہ سیال ہونے کے جس برتن میں ڈالا جاتا ہے اس کی شکل اختیار کر لیتا ہے مگر کون
عظمند ہے جو یہ کہے کہ اس میں کیا حرج ہے کہ پانی کی طرح پتھر کے متعلق بھی یہ سمجھ لیا
جائے کہ وہ بھی جس برتن میں رکھا جاویگا اس کی شکل اختیار کر لیگا ؟ یہ نادانی اور جہالت
کی باتیں ہیں جن کی طرف کوئی ہوش و حواس رکھنے والا انسان توجہ نہیں کر سکتا.پس خدا
غیر مخلوق ہے اس لئے کہ وہ مخلوق نہیں ہوسکتا.یعنی اس کے لئے ناممکن ہے کہ وہ مخلوق ہو
کیونکہ مخلوق ہونے سے وہ خدا نہیں رہتا ( جیسا کہ پتھر کے لئے یہ ناممکن ہے کہ وہ پانی
کی طرح جس برتن میں ڈالا جائے اس کی شکل وصورت اختیار کر لیا کرے کیونکہ ایسا
کرنے سے وہ پتھر نہیں رہتا ) مگر اس دُنیا کی کسی چیز کے لئے مخلوق ہونا اس کی کسی طبعی
صفت کے خلاف نہیں ہے.پس فرق ظاہر ہے.اب تک میں نے صرف یہ بتایا ہے کہ دُنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں جسے مخلوق قرار
دینے سے اس کی کسی صفت کا انکار کرنا پڑے اور چونکہ عام اصول یہی ہے کہ جب تک
کسی چیز کو مخلوق قرار دینے سے رستہ میں کوئی طبعی روک نہ ہوا سے مخلوق ماننا چاہیئے اس
لئے ثابت ہوا کہ یہ دُنیا مخلوق ہے.اب میں مختصر طور پر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نہ صرف یہ
کہ دُنیا کے مخلوق مانے جانے کے رستہ میں کوئی روک نہیں بلکہ دنیا کے حالات ایسے ہیں
کہ وہ ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ ہم اسے مخلوق قرار دیں.مثلاً
اول یہ کہ دنیا میں کثرت ہے.یعنی دنیا کسی ایک چیز کا نام نہیں بلکہ بے شمار
چیزوں کے مجموعہ کا نام ہے اور یہ عظیم الشان کثرت جس کے حصر پر انسان آج تک قادر
نہیں ہو سکا اور نہ کبھی ہو سکے گا اس بات کا تقاضا کر رہی ہے کہ دنیا کا کوئی خالق و مالک
105
Page 106
اوپر
ہونا چاہئے جو ان کثیر التعداد افواج کو ایک واحد نظام کے ماتحت جمع رکھ سکے.لیکن
اس کے مقابلہ میں خدا کا وجود مذہباً بھی اور عقلاً بھی واحد بلکہ احد مانا جاتا ہے جس کے
او پر کسی منظم یعنی ایک انتظام میں جمع رکھنے والی ہستی کی ضرورت نہیں.دوسرے دنیا میں اختلاف ہے یعنی دنیا کسی ایک قسم کی چیزوں کے مجموعہ کا نام
نہیں بلکہ بیشمار مختلف الصورت اور مختلف الجنس چیزوں پر مشتمل ہے جن میں سے ہر
ایک الگ الگ خواص
رکھتی اور الگ الگ دائرہ میں چکر لگاتی اور الگ الگ قانون کے
ماتحت جاری ہے.پس یہ اختلاف بھی ایک خالق و مالک قدیر و متصرف ہستی کی ضرورت
کو ثابت کر رہا ہے جو اِن لاتعداد مختلف چیزوں کو باوجود ان کے الگ الگ قانون کے
انہیں ایک مجموعی قانون کی لڑی میں پرو سکے.مگر خُدا کی ذات کے متعلق بوجہ ایک
ہونے کے اختلاف کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوسکتا.تیسرے دنیا کی ہر چیز کو زوال اور تغیر لاحق ہے.یعنی دُنیا کی کوئی چیز ایسی
نہیں جو ایک حالت پر قائم رہتی ہو بلکہ ہر چیز ہر وقت بدل رہی ہے اور ہر وقت ہر چیز
اپنی محدود عمر کی گھڑیوں کو کم کرتی چلی جارہی ہے.اور یہ حالت بھی اس بات کا ثبوت
ہے کہ یہ دنیا خود بخود نہیں بلکہ کسی بالا ہستی کے قبضہ و تصرف کے ماتحت ہے ،لیکن خدا کا
وجود غیر متغیر اور زمانہ کے اثر سے بالا ہے اور بالا ہونا چاہئے.چوتھے دُنیا کی ہر چیز اپنی طاقتوں اور اپنے طبعی قوی اور اپنے دائرہ عمل میں
محدود اور مقید ہے.اور دُنیا کی کوئی چیز بھی ایسی نہیں جس کی کوئی ایک صفت بھی ایسے
درجہ کمال تک پہنچی ہوئی ہو کہ حدود و قیود سے آزاد ہو جائے.پس خواص وصفات کی یہ
حد بندی بھی ایک حد مقرر کرنے والی ہستی پر دال ہے یعنی ایک ایسی ہستی کی طرف
اشارہ کر رہی ہے جس نے ان بیشمار مختلف چیزوں کو ایک قانون کے ماتحت معتین حدود
کے اندر محدود کر رکھا ہے اور جو خود ہر قید و بند سے آزاد ہے.106
Page 107
پانچویں دُنیا کی کوئی چیز قائم بالذات نہیں بلکہ اپنے قیام کے واسطے دوسروں
کے سہارے کی محتاج ہے.اور سائنس کی جدید تحقیقاتوں نے تو اس بات کو یہاں تک
ثابت کر دیا ہے کہ دُنیا کی ہر اک چیز اپنی زندگی کے قیام کے واسطے باقی تمام دوسری
چیزوں پر اثر ڈال رہی اور اُن سے اثر لے رہی ہے.گویا کوئی چیز بھی اپنی ذات میں
قائم نہیں.پس دُنیا کی ہر ایک چیز کا غیر قائم بالذات ہونا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ
یہ دنیا خود بخود اپنے آپ سے نہیں بلکہ کسی بالا ہستی کے سہارے پر قائم ہے جس نے
ایک حکیمانہ نظام میں ہر اک چیز کو اپنی اپنی جگہ میں قائم کر رکھا ہے.چھٹے دُنیا میں ایک خاص ڈیزائن (Design) یعنی ترتیب پائی جاتی ہے جو ایک
مدرک بالا رادہ مرتب ہستی کو چاہتی ہے لیکن خُدا کے متعلق یہ سوال پیدا نہیں ہوتا.ساتو میں دنیا کی ہر چیز اپنے حالات سے ایک خاص غرض و مقصد کے ماتحت چلتی
ہوئی نظر آتی ہے.اور یہ علت غائی جو نیچر کے مطالعہ سے ہر چیز کے دور زندگی میں ظاہر
ہو رہی ہے اس بات کو چاہتی ہے کہ اس عالم کے پیچھے ایک اور ہستی ہو جو خود پس پردہ رہ کر
نظام عالم کی غیر مرئی تاروں کو ہر وقت اپنے ہاتھ میں رکھتی ہے اور ایک معین پروگرام کے
ماتحت اس دُنیا کو ایک خاص مقصد و منتہجی کی طرف لے جارہی ہے.لیکن اس کے مقابلہ
میں خُدا کے وجود کے متعلق قطعاً کوئی علت غائی کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا کیونکہ وہ اپنی
ذات میں واحد و احد.اول و آخر قائم وصمد اور جامع و جمیع کمالات مانا جاتا ہے.اسی
طرح دُنیا کے باقی تمام حالات وکوائف بھی اس کے مخلوق ہونے پر دلالت کر رہے ہیں.الغرض دُنیا کے حالات ہمیں اس بات پر مجبور کر رہے ہیں کہ ہم اسے مخلوق
و مملوک قرار دیں مگر اس کے مقابل میں خدا کی صفات نہ صرف یہ کہ اس کے مخلوق ہونے
کے متقاضی نہیں بلکہ خدائیت اور مخلوقیت کا مفہوم اس طرح ایک دوسرے کی ضد میں
واقع ہوا ہے کہ کبھی بھی ایک وجود میں جمع نہیں ہوسکتا.پس یہ نادانی اور لاعلمی کا سوال
107
Page 108
ہے کہ اگر خدا غیر مخلوق ہو سکتا ہے تو کیوں نہ اس دُنیا کو ہی غیر مخلوق سمجھ لیا جائے اور حق
یہی ہے کہ ہر اک چیز مخلوق ہے.مگر خدا جس کے اوپر کوئی خالق نہیں اور ہر اک چیز
م ہے مگر خدا جس کے اوپر کوئی حاکم نہیں اور ہر اک چیز مملوک ہے.مگر خدا جس کے
او پر کوئی مالک نہیں خدا کی ذات وہ مرکزی نقطہ ہے جس پر تمام خطوط جمع ہوتے ہیں اور
جس کے آگے کوئی رستہ نہیں.مبارک وہ جو اس نقطہ کو پہچانتا ہے اور ہلاکت کے گڑھے
میں گرنے سے بچ جاتا ہے.حدیث شریف میں بھی آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول آتا ہے کہ تم ہر چیز
کے متعلق یہ پوچھ سکتے ہو کہ اسے کس نے پیدا کیا ہے لیکن جب خدا پر پہنچ تو پھر اس
سوال کو بند کر دو.کوئی نادان خیال کرتا ہوگا کہ آپ نے اپنے متبعین کے لئے آزادانہ
تحقیق کا راستہ بند کرنا چاہا ہے اور گو یا شکوک سے بچانے کے لئے ان کو اس علمی سوال
میں پڑنے سے ہی روک دیا ہے.حالانکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی منشا ہے
جو او پر بیان کیا گیا ہے یعنی یہ کہ ہر چیز کے متعلق مخلوق ہونے کا سوال پیدا ہو سکتا ہے مگر
خُدا کے متعلق یہ سوال پیدا نہیں ہوسکتا.اور اگر کوئی شخص یہ سوال اُٹھاتا ہے تو یہ اس کی
اپنی جہالت کا ثبوت ہے.پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کا دروازہ بند نہیں کیا
بلکہ جہالت کا دروازہ بند کیا ہے.تحقیق کے رستہ میں روک نہیں ڈالی بلکہ تو ہم پرستی میں
پڑنے سے منع فرمایا ہے.اللهم صلّ عليه وسلّم وياايها الذين امنوا صلّوا
عليه وسلّموا تسليماً.خلاصہ کلام یہ کہ یہ وسیع عالم معہ اپنے نہایت درجہ حکیمانہ نظام کے جو اس کی
کثیر التعداد مختلف الجنس ، تغیر پذیر، غیر قائم بالذات محدود اشیاء میں انفرادی اور مجموعی
طور پر کام کرتا نظر آتا ہے زبانِ حال سے اس بات کی شہادت پیش کر رہا ہے کہ وہ
خود بخود اپنے آپ سے نہیں ہے بلکہ ایک بالا ہستی کی قدرت خلق سے عالم وجود میں آیا
108
Page 109
ہے اور اسی بالا ہستی کے سہارے پر قائم اور جاری ہے اور یہ بالا ہستی خود غیر مخلوق اور
غیر مملوک ہے کیونکہ یہ وہ آخری نقطہ ہے جس پر تمام سلسلے ختم ہوتے ہیں.حضرت
مسیح موعود علیہ السلام کی ایک لطیف نظم پر اس دلیل کی بحث کو ختم کرتا ہوں :.کس قدر ظاہر ہے نُور اس مبداء الانوار کا
بن رہا ہے سارا عالم آئینہ ابصار کا
چاند کو کل دیکھ کر میں سخت بیکل ہو گیا
کیونکہ کچھ کچھ تھا نشاں اس میں جمال یار کا
اس بہارِ حسن کا دل میں ہمارے جوش
مت کرو کچھ ذکر
ہم
ترک
ہے
یا تا تار کا
ہے عجب جلوہ تری قدرت کا پیارے ہر طرف
جس طرف دیکھیں وہی راہ ہے ترے دیدار کا
چشمه خورشید میں موجیں تری مشہور ہیں
ہر ستارے میں تماشہ ہے تیری چمکار کا
ٹو نے خود رُوحوں پہ اپنے ہاتھ سے چھڑکا نمک
اس سے ہے شورِ محبت عاشقان زار کا
کیا عجب تو نے ہر اک ذرہ میں رکھے ہیں خواص
کون پڑھ سکتا ہے سارا دفتر ان اسرار کا
تیری قدرت کا کوئی بھی انتہا پاتا نہیں
کس سے کھل سکتا ہے بیچ اس عقدہ دشوار کا
ب رویوں میں ملاحت ہے ترے اس حُسن کی
ہر گل و گلشن میں ہے رنگ اس تری گلزار کا
109
Page 110
مست ہر حسیں ہر دم دکھاتی ہے مجھے
ہاتھ ہے تیری طرف ہر گیسوئے خمدار کا
آنکھ کے اندھوں کو حائل ہوگئے سو سو حجاب
ورنہ قبلہ تھا تیرا رُخ کافر و دین دار کا
ہیں تری پیاری نگاہیں دلبرا اک تیغ تیز
جس سے کٹ جاتا ہے سب
جاتا ہے سب جھگڑا غم اغیار کا
تیرے ملنے کے لئے ہم مل گئے ہیں خاک میں
تا مگر درماں ہو کچھ اس ہجر کے آزار کا
ایک دم بھی کل نہیں پڑتی مجھے تیرے سوا
جاں گھٹی جاتی ہے جیسے دل گھٹے بیمار کا
شور کیسا ہے ترے کوچے میں لے جلدی خبر
خوں نہ ہو جائے کسی دیوانہ مجنوں وار کا
نیکی بدی کے شعور کی دلیل
اس کے بعد جو عقلی دلیل ہستی باری تعالیٰ کے متعلق میں اس جگہ پیش کرنا چاہتا
ہوں وہ اس اخلاقی قانون سے تعلق رکھتی ہے جو ہر انسان کی فطرت میں مرکوز ہے.گویا
جیسا کہ گذشتہ دلیل اس طبعی قانون سے تعلق رکھتی تھی جو انسان اور اس عالم دنیوی کی
دوسری چیزوں میں انفرادی اور مجموعی طور پر کام کرتا ہوا نظر آتا ہے.اسی طرح یہ دلیل جو
میں اب بیان کرنا چاہتا ہوں اس اخلاقی قانون پر مبنی ہے جو ہر فرد بشر کی فطرت میں
کام کر رہا ہے اور جس کے وجود سے کوئی عقلمند انکار نہیں کر سکتا.نیکی بدی کا شعور انسان
کی فطرت کے اندر مرکوز ہے اور کوئی انسان بھی ایسا نہیں ملے گا جس کے اندر یہ شعور
110
Page 111
مفقود ہو.بیشک یہ ممکن ہے کہ کسی انسان کی فطرت بیرونی اثرات کے نتیجہ میں کمزور
ہو جائے یا ایسی طرح دب جائے کہ گویا وہ بالکل مر ہی گئی ہے لیکن پھر بھی کسی نہ کسی رنگ
میں کسی نہ کسی صورت میں کسی نہ کسی موقع پر وہ ظاہر ہوئے بغیر نہیں رہتی.ہر انسان خواہ
اس کی حالت کیسی ہی بری ہو فطرۂ نیکی کو پسند کرتا اور بدی کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا
ہے.بیشک ایک نہایت شقی القلب پر انا عادی چور جس نے چوری کر کر کے اور لوگوں
کے اموال کو اُن سے ناجائز طور پر چھین چھین کر اپنی فطرت کو گناہ کے تاریک و تار
پردوں میں دفن کر رکھا ہو بسا اوقات لوگوں کے طعنوں سے تنگ آکر یا اپنے آپ کو اپنے
ضمیر کے مخفی نشتروں سے بچانے کے لئے ڈھیٹ بن کر ایسی باتیں کہنے لگ جاتا ہے کہ
میرا چوری کرنا کوئی بُر افعل نہیں کیونکہ جس طرح لوگ مختلف پیشے اختیار کر کے اپنی روزی
کماتے ہیں اسی طرح میں بھی محنت کر کے اور اپنی جان کو مشقت اور خطرہ میں ڈال کر
اپنا اور اپنے اہل وعیال کا پیٹ پالتا ہوں لیکن باوجود اس کے اس پر ایسے اوقات ضرور
آتے رہتے ہیں کہ جب اس کی فطرت اُسے ملامت کرتی ہے کہ تیرا یہ فعل نا واجب اور
ظالمانہ ہے.یہی وجہ ہے کہ بسا اوقات جب ایک چور جوانی سے نکل کر بڑھاپے میں
قدم رکھتا ہے اور موت اُسے قریب نظر آتی ہے تو وہ چوری کی زندگی کو ترک کر کے اپنے
ضمیر سے صلح کرنے کی طرف متوجہ ہوجاتا ہے اور اگر کسی شخص کی فطرت بالکل ہی
خاموش ہو چکی ہوتی کہ وہ اپنی بداعمالیوں کو ہی اپنے لئے موجب فخر سمجھنے لگ جائے اور
بظاہر حالات ایسا نظر آئیں کہ اس کے اندر نیکی بدی کا شعور بالکل ہی مفقود ہو چکا ہے تو
پھر بھی نظر غائر سے دیکھنے والوں پر یہ بات مخفی نہیں رہے گی کہ ایسا شخص بھی اس فطری
جو ہر سے خالی نہیں ہے جو نیکی بدی کے شعور سے موسوم ہوتا ہے کیونکہ گو دوسروں کے
ساتھ معاملہ کرنے میں وہ بالکل مُردہ فطرت نظر آتا ہے لیکن جب یہ سوال پیدا ہوتا ہے
کہ اُس کے ساتھ دوسرے لوگ کس طرح معاملہ کریں تو اُس کی دبی ہوئی فطرت تمام
111
Page 112
پر دوں کو پھاڑ کر باہر نکل آتی ہے اور وہ اس بات کے لئے ہرگز تیار نہیں ہوتا کہ اپنا
چھوٹے سے چھوٹا حق بھی جو وہ نیکی بدی کے شعور کے ماتحت سمجھتا ہے کہ اُسے حاصل
ہے ترک کر دے.مثلاً دوسروں کا مال چرانے میں ایک پرانا عادی چور جس نے چوری
کر کر کے اپنی فطرت کو مار رکھا ہو اپنے آپ کو حق بجانب سمجھ سکتا ہے یا کم از کم یہ ظاہر
کر سکتا ہے کہ میں حق بجانب ہوں لیکن اگر دوسرا کوئی شخص اس کے مال پر ہاتھ ڈالے تو
فوراً اس کی نیم مردہ فطرت جوش میں آکر اپنے حقوق کی حفاظت کے لئے کھڑی ہو جاتی
ہے.اسی طرح ایک زانی جو دوسروں کی بہو بیٹیوں اور بہنوں اور بیویوں کو خراب کرنے
کے درپے رہتا ہے اور بعض اوقات اپنے اس گندے فعل میں ایسا انہماک پیدا کر لیتا
ہے کہ اگر کوئی شخص اسے اس حرکت سے باز رکھنے کی کوشش کرے تو وہ بے شرم بن کر
یہاں تک کہہ دیتا ہے کہ یہ کوئی بُرا کام نہیں ہے جو میں فریق ثانی کی رضامندی سے کرتا
ہوں اور دوسروں کو اس سے کوئی سروکار نہیں.لیکن جب خود اس کے اندرون خانہ پر کوئی
دوسرا بد بخت ہاتھ ڈالتا ہے تو پھر اُس کی آنکھوں میں خون اتر آتا ہے اور وہ یہ بات
بُھول جاتا ہے کہ اگر مجھے اپنی خوشی کے پورا کرنے کا حق ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ دوسرا
شخص بھی اپنی خوشی پوری نہ کرے.اسی طرح ایک کذاب اور دروغگو انسان دوسروں کو
دھوکا دیکر خوش ہو سکتا ہے لیکن جب کوئی شخص جھوٹ بول کر خود اُسے دھوکے میں ڈالتا
ہے تو وہ غیظ و غضب سے بھر کر انتقام لینے کے درپے ہو جاتا ہے.الغرض نیکی بدی کا شعور فطرۃ ہر انسان کے اندر موجود ہے اور یہ شعور اس بات
کی ایک زبردست دلیل ہے کہ انسان خود بخود کسی اتفاق کا ثمرہ نہیں اور نہ کسی اندھے
قانون
کا نتیجہ ہے بلکہ ایک علیم وحکیم ہستی نے اسے ایک خاص غرض کے ماتحت پیدا کیا
ہے اور وہ غرض یہی ہے کہ انسان اپنے اس فطری شعور کو جو بطور ایک تخم کے اس کے اندر
رکھا گیا ہے نشو ونما دیکر اپنے لئے اعلیٰ ترقیات کے دروازے کھولے اور اس کامل منبع
112
Page 113
حُسن و احسان اور اس وحید چشمہ حیات یعنی ذات باری تعالیٰ کا عکس اپنے اندر پیدا کرتا
ہوا ابد الآباد کے لئے ہر قسم کے حسن و احسان کی بلند ترین چوٹیوں کی طرف چڑھتا چلا
جائے.خوب غور کرو کہ یہ نیکی بدی کا شعور جو ہر انسان کی فطرت میں مرکوز ہے اور یہ خفی
نور قلب جس کا چشمہ ہر ابن آدم کے سینہ سے ابل ابل کر پھوٹ رہا ہے کبھی کسی
اندھے اتفاق یا کسی غیر شعوری ارتقاء کا نتیجہ نہیں ہوسکتا بلکہ اس سے صاف ثابت ہوتا
ہے کہ اس فطری جذبے کو پیدا کرنے والی ایک مدرک بالا رادہ ہستی ہے جس نے
انسان کو اس غرض کے لئے پیدا کیا ہے کہ وہ اس فطری جذبے کو ترقی دیکر اعلیٰ انعامات کا
وارث بنے.میں نہیں سمجھ سکتا کہ کوئی شخص جو ذرا بھی فکر و تدبر کا مادہ رکھتا ہے نیکی بدی
کے اس فطری شعور کو جو ہر انسان میں پایا جاتا ہے اور جس کے ماتحت انسان سے ہمیشہ
طبعی طور پر بعض نیک افعال سرزد ہوتے رہتے ہیں محض کسی اتفاقی قانون یا فطری ارتقاء
کا نتیجہ قرار دے سکتا ہے.بعض لوگ کہتے ہیں کہ دُنیا ایک مشین کی طرح ہے جس کے مختلف پُرزے اس
مشین کی اندرونی صنعت کے ماتحت خود بخود اپنے اپنے حلقہ میں چلتے رہتے ہیں اور
اس سے وہ یہ استدلال کرتے ہیں کہ خدا کوئی نہیں ہے.ایسے لوگ دیانتداری کے
ساتھ غور کریں کہ کیا یہ فطری شعور جس سے ہر انسان نیکی کے اختیار کرنے کی طرف
رغبت محسوس کرتا ہے کسی اندھی میکانزم (Mechanism) کا نتیجہ ہوسکتا ہے؟ کیا کوئی
ایسی مشین ہے یا ہوسکتی ہے جو خود بخود اپنی کسی اندرونی طاقت سے ایسے رنگ میں چلے
کہ وہ غریب اور امیر - خوش بخت اور مصیبت زدہ.جوان اور بوڑھے.کمزور اور توانا.یتیم اور غیر یتیم کے معاملہ میں فرق کرتی جائے.مثلاً اگر آٹے کی مشین ہو تو ایک غریب
یا مصیبت زدہ شخص یا بوڑھے یا کمزور شخص یا ایک یتیم بچہ کا آٹا زیادہ اچھا اور زیادہ جلدی
پیس دے اور ایک امیر اور خوشحال اور جوان اور توانا اور زندہ والدین رکھنے والے بچہ کا
113
Page 114
کام صرف معمولی طور پر کرے ؟ اگر کوئی ایسی مشین نہیں ہے اور نہ ہو سکتی ہے تو کیا انسانی
قلب میں فطری طور پر نیکی بدی کے شعور کا ہونا اور انسان کا فطرۂ نیکی کو پسند کرنا اور
حالات کے مناسب رحم کھانا اور محبت دکھانا یا عفو سے کام لینا یا مصیبت زدہ کی امداد کرنایا
قربانی اور ایثار دکھانا اس بات کا ثبوت نہیں کہ انسان کی زندگی خود بخود مشین کے طور پر
کام نہیں کر رہی بلکہ اس کے پیچھے ایک اور ہستی ہے جس نے یہ جذبات ایک خاص
غرض و غایت کے ماتحت اس کی فطرت میں مرکوز کئے ہیں؟
اسی طرح یہ ایک فطری خاصہ ہے کہ انسان بدی کو نفرت کی نظر سے دیکھتا ہے حتی
کہ کبھی جب خود اس سے بھی غفلت یا جوش کی حالت میں بدی کا ارتکاب ہوتا ہے تو بعد
میں وہ اپنے قلب کے اندر پشیمانی اور ندامت کو محسوس کرتا ہے اور یہ کیفیت بھی اس بات
کا ثبوت ہے کہ انسانی زندگی ایک محض مشین کے طور پر
نہیں بلکہ کسی بالا ہستی نے اسے
ایک خاص مقصد کے ماتحت پیدا کیا ہے اور اس کے قلب کے قلعہ پر یہ فطری پہرہ دار
کسی خاص غرض و غایت کے ماتحت کھڑے کئے گئے ہیں.انسان کے سینہ میں بیسیوں
جذبات کا خزانہ مرکوز ہے اور ہر جذبہ کے متعلق یہ شعور بھی اُس کی فطرت کے اندر بطور تخم
کے ودیعت کیا گیا ہے کہ اس جذبہ کا یہ استعمال اچھا ہے اور وہ استعمال بُرا ہے اور یہ کہ
اسے ہمیشہ اچھے استعمال کو اختیار کرنا چاہئے اور بُرے استعمال کو نفرت کی نظر سے دیکھنا
چاہئے اور شریعت ہمیشہ فطرت انسانی کے انہی مخفی تخموں کی آبپاشی کرنے اور ان کے
اُگانے اور ترقی دینے کے لئے نازل کی جاتی ہے.الغرض فطرت انسانی کے اندر نیکی
بدی کا شعور موجود ہونا اس بات کا ایک زبر دست ثبوت ہے کہ انسان خود بخود اپنے آپ
سے نہیں ہے اور یہ کہ اس کی زندگی ایک مشین کے طور پر نہیں چل رہی بلکہ اس کے پیچھے
ایک مدرک بالا رادہ ہستی کا ہاتھ ہے جس نے اُسے ایک خاص غرض و غایت کے ماتحت
پیدا کیا ہے.وھوالمراد.114
Page 115
اگر اس جگہ کسی کو یہ اعتراض پیدا ہو کہ کیا یہ ممکن نہیں کہ یہ شعور جسے فطری شعور کہا
جاتا ہے گرد و پیش کے حالات اور خاندانی اور ملکی روایات کا نتیجہ ہو؟ یعنی اگر لوگ نیکی کو
اچھا سمجھتے اور بدی سے نفرت کرتے ہیں تو اس کی وجہ کوئی فطری تقاضا نہ ہو بلکہ محض یہ
وجہ ہو کہ لوگوں نے تجربہ سے اچھے کاموں کو اچھا سمجھ لیا ہو اور بُرے کاموں کو بُرا.اور
اس طرح آہستہ آہستہ ایک لمبے عرصہ کے بعد یہ خیال نسلِ انسانی میں قائم وراسخ ہو کر
ایک فطری شعور کے طور پر نظر آنے لگ گیا ہو؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ گو یہ اعتراض
بظاہر قابل غور نظر آتا ہے لیکن ذرا تدبر اور فکر سے کام لیا جاوے تو حقیقت حال ہرگز مخفی
نہیں رہ سکتی.ظاہر ہے کہ نیکی بدی کا احساس دو ہی طرح پیدا ہوسکتا ہے.یعنی یا تو اس کا
باعث ایک لمبے زمانہ کا تجربہ اور گردو پیش کے حالات ہیں جیسا کہ معترض کا خیال ہے
اور یا وہ کسی بالا ہستی کی فطری ودیعت ہے جیسا کہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے.ان دو کے سوا
کوئی تیسری صورت ذہن میں نہیں آتی اور اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ان دونوں
صورتوں میں سے کونسی صورت صحیح اور حقیقت پر مبنی ہے.سوسب سے پہلی بات جو نیکی
بدی کے شعور میں ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس شعور کے اندر خواہ وہ دُنیا کی کسی قوم
اور کسی زمانہ کے ساتھ تعلق رکھتا ہو ایک رنگ کی ایک صورتی نظر آتی ہے جسے انگریزی
میں یونی فارمیٹی (Uniformity) کہتے ہیں.یعنی یہ شعور دنیا کی ہر قوم میں اور دُنیا
کے ہر زمانہ میں اپنی اصل کے لحاظ سے ایک ہی صورت اور ایک ہی رنگ ڈھنگ کا نظر
آتا ہے جو اس بات کا بین ثبوت ہے کہ وہ تجربہ اور گردو پیش کے حالات کے نتیجہ میں
پیدا نہیں ہوا بلکہ کسی بیرونی طاقت کی طرف سے جو سب پر بالا اور فائق ہے
فطرت انسانی میں ودیعت کیا گیا ہے.خوب سوچ لو کہ جو بات تجر بہ اور گردو پیش کے
حالات سے پیدا ہوتی ہے وہ ضرور مختلف قوموں اور مختلف زمانوں میں مختلف ہونی
چاہئے خصوصاً ابتدائی زمانہ میں جبکہ ہر قوم عموماً ہر دوسری قوم سے بے خبر ہوتی تھی اور
115
Page 116
ایک دوسرے کے ساتھ میل جول اور اختلاط کے ذرائع مفقود تھے یہ شعور لازماً مختلف
اقوام میں مختلف صورتوں میں پیدا ہونا چاہئے تھا.کیونکہ ہر قوم کا تجربہ اور ہر قوم کے
حالات ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں.چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ قومی
عادات وطوار جو یقیناً گر دو پیش کے حالات کا نتیجہ ہوتے ہیں ہر قوم میں مختلف نظر آتے
ہیں.پس اگر نیکی بدی کا شعور بھی اقوام کے حالات
اور تجربہ کا نتیجہ ہوتا تو یہ ضروری تھا
کہ وہ ہر قوم اور ہر زمانہ میں مختلف صورتوں میں نظر آتا.لیکن ایسا نہیں ہے بلکہ واقعہ یہ
ہے کہ یہ شعور دنیا کی ہر قوم اور ہر زمانہ میں ہمیشہ یک صورتی یعنی یونی فارمیٹی
(Uniformity) کی حالت میں پایا گیا ہے.مثلاً اگر ہم دُنیا کی دو ایسی قوموں کولیس
جن کے حالات بالکل ایک دوسرے سے مختلف ہیں مثلاً ایک بہت متمدن اور تعلیم یافتہ
اور مہذب ہو اور دوسری بالکل وحشی اور جاہل اور غیر مہذب ہو تو دونوں میں باوجوداس
درجہ اختلاف کے یہ شعور جہاں تک مجر دشعور کا تعلق ہے اصولاً بالکل ایک جیسا اور ایک
ہی صورت و شکل کا نظر آئے گا اور اگر اختلاف ہوگا تو صرف ان معاملات میں ہوگا جو
بعد کے نشو ونما سے تعلق رکھتے ہیں.یعنی ایک قوم میں یہ فطری شعور ایک خاص رنگ
میں اور خاص رستہ پر نشو ونما پایا ہوا معلوم ہوگا اور دوسری قوم میں وہ دوسرے رنگ میں
اور دوسرے رستہ پر نظر آئے گا مگر جب ان کو بعد کے تاثرات سے الگ کر کے ان کی
اصل کے لحاظ سے دیکھا جائے گا تو دونوں میں ایک ہی صورت اور ایک ہی رنگ
ڈھنگ نظر آئیں گے.اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ شعور اپنی اصل کے لحاظ سے
حالات اور تجربات کا نتیجہ نہیں بلکہ ایک فطری ودیعت ہے جس سے کوئی ابنِ آدم محروم
نہیں.دوسری دلیل اس بات کی کہ یہ شعور ایک فطری امر ہے اور کسی خارجی اثر کا نتیجہ
نہیں یہ ہے کہ اگر نظر غور سے دیکھا جائے تو بعض ایسے معاملات میں بھی یہ شعور انسان
116
Page 117
شعور
کے اندر کام کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ جو کسی عظمند کے نزدیک تجر بہ اور گرد و پیش کے حالات
کا نتیجہ نہیں ہو سکتے یعنی وہ معاملات اپنی نوعیت میں ایسے ہیں کہ کسی صورت میں بھی
ان
کا نفع یا نقصان انسانی تجربہ میں آکر معلوم نہیں ہوسکتا اور اس لئے اگر ان کے متعلق
کوئی شعور پایا جاتا ہے تو وہ ہرگز حالات یا تجربہ کا نتیجہ نہیں کہلا سکتا بلکہ لاریب ایسے شعور
کا منبع کوئی بالا طاقت سمجھی جائے گی جس نے خاص حکمت کے ماتحت یہ شعور ہر انسان کی
فطرت میں ودیعت کر رکھا ہے.مثلاً ہم دیکھتے ہیں کہ مُردہ کا احترام کسی نہ کسی صورت
میں ہر قوم اور ہر زمانہ میں پایا جاتا رہا ہے.لیکن ظاہر ہے کہ یہ شعور اپنی نیچر کے لحاظ سے
ایسا ہے کہ ایسے تجربہ اور گردوپیش کے حالات سے قطعا کوئی تعلق نہیں اور اسے سوائے
فطرت کی آواز کے کسی اور طرف منسوب نہیں کیا جاسکتا.خلاصہ کلام یہ کہ بعض ایسی
باتوں میں نیکی بدی کا شعور پایا جانا جن کا نفع نقصان کبھی بھی تجربہ میں آکر معلوم نہیں ہوا
اور نہ جن میں بظاہر کوئی مادی فائدہ نظر آتا ہے اس بات کا ایک بین ثبوت ہے کہ یہ شہ
تجربہ اور حالات
کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ ایک فطری امر ہے جو کسی بالا ہستی نے ہر انسان کی
فطرت میں ودیعت کر رکھا ہے.وهو المراد
تیسری دلیل اس بات کی کہ نیکی بدی کا شعور ایک فطری شعور ہے یہ ہے کہ یہ
شعور بعض صورتوں میں قومی روایات کے خلاف بھی ظاہر ہوتا ہے جس سے یہ بات ط
طور پر ثابت ہو جاتی ہے کہ وہ قومی روایات کا نتیجہ نہیں کیونکہ نتیجہ بھی بھی نتیجہ پیدا کرنے
والی چیز کے مخالف نہیں ہوسکتا.تاریخ میں ایسی بہت سی مثالیں ملتی ہیں کہ مثلاً ایک قوم
ایک لمبے زمانہ کے حالات کے ماتحت اپنے اندر سخت دلی پیدا کر لیتی ہے اور اس کے
افراد میں ظلم وستم اور سخت گیری کی طرف میلان پیدا ہو جاتا ہے اور قومی روایات ہر
فرد قوم کو سنگدل اور بے رحم اور قسی القلب بنادیتی ہیں لیکن بائیں ہمہ اگر اس کے افراد کی
فطرت اور سائیکالوجی کا گہرا مطالعہ کیا جائے اور ان کے سوانح زندگی کو غور سے دیکھا
117
طعی
Page 118
جائے تو باوجود اس سنگدلی کے پردہ کے جس نے ان کو ڈھانپا ہو ا ہوتا ہے ان کے اندر
رحم کا جذ بہ بھی ضرور نظر آئے گا اور کسی نہ کسی وقت کسی نہ کسی صورت میں پیخفی جذ بہ اپنی
جھلک دکھا جائے گا.اسی طرح ایسی مثالیں بھی موجود ہیں کہ ایک قوم ایک لمبے عرصہ
تک ایسے حالات میں سے گذری ہے جس نے اس کے اندر رحم اور عفو اور نرمی کے
خیالات کی پرورش کی ہے اور اس کے ہر فرد کے لئے قومی روایات صرف رحم سے وابستہ
ہو گئی ہیں لیکن اگر غور سے دیکھا جائے گا تو معلوم ہوگا کہ باوجود ان حالات کے ایسی قوم
کے ہر فرد میں یہ جذبہ پایا جائے گا کہ اگر اصلاح کی صورت سختی اور گرفت کے ساتھ
ہوتی ہو اور عفو کرنا اور رحم دکھانا نقصان کا موجب ہو تو ایسی صورت میں عفو اور رحم سے کام
نہ لینا چاہئے بلکہ گرفت اور مناسب سزا کا طریق اختیار کرنا چاہیئے.الغرض نیکی بدی کا
یہ فطری شعور بعض اوقات قومی روایات اور ملکی حالات کے خلاف بھی پایا جاتا ہے کیونکہ
وہ فطرت کا حصہ ہے اور فطرت گو حالات کے اثر کے نیچے آکر دب جائے مگر کبھی بھی وہ
بالکل مُردہ نہیں ہوسکتی اور اسی لئے بسا اوقات یہ منظر دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک شخص کے
قومی یا خاندانی حالات و روایات اس کی طبیعت کو ایک خاص رنگ میں ڈھال دیتے ہیں
اور گویا ان حالات وروایات کے نتیجہ میں اس کے اندر ایک نئی فطرت قائم ہو جاتی ہے
جسے فطرت ثانیہ کہہ سکتے ہیں مگر پھر بھی جب اصلی فطرت کو کوئی تحریک ملتی ہے تو وہ ایک
بند آتش فشاں پہاڑ کی طرح فطرت ثانیہ کے پردوں کو پھاڑ کر باہر آ جاتی ہے.خلاصہ کلام یہ کہ بیشک حالات وروایات کے ماتحت بھی ایک رنگ کی فطرت قائم
ہو جاتی ہے لیکن یہ فطرتِ ثانیہ ہے نہ کہ فطرتِ اصلیہ.اور فطرتِ اصلیہ وہی ہے جس کو
حالات وروایات
ملکی یا تجربات قومی کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے بلکہ وہ ہر انسان کی
خلقت کا حصہ ہے اور یہ فطرتِ اصلیہ جس کے اندر ایک نہایت حکیمانہ رنگ میں نیکی
بدی کا شعور ودیعت کیا گیا ہے اس بات کا ایک روشن ثبوت ہے کہ اس کے پیچھے ایک
118
Page 119
مدرک بالا رادہ خالقِ فطرت ہستی کا ہاتھ ہے جس نے ایک خاص غرض و غایت کے
ماتحت یہ جو ہر اس کے اندر مرکوز کر دیا ہے.چنانچہ قرآن شریف فرماتا ہے:.فَالْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوهَا
یعنی ” خدا نے ہر انسان کی فطرت میں بدی اور نیکی کا شعور رکھ دیا ہوا ہے اور
اُسے اس کی فطرت کے ذریعے بتا دیا ہے کہ یہ راستہ بُرا ہے اور یہ راستہ اچھا ہے.“
اور دوسری جگہ فرمایا ہے:
وَهَدَيْناهُ النَّجْدَيْنِ
یعنی ” ہم نے انسان کو نیکی اور بدی ہر دو کے رستے (اس کی فطرت کے ذریعہ) دکھا
دیئے ہوئے ہیں.اور اب یہ اس کا کام ہے کہ وہ چاہے تو نیکی کے رستہ کو اختیار کرے اور چاہے تو
ط
بدی کے رستہ پر پڑ جائے.ایک اور جگہ کھلے الفاظ میں فرماتا ہے:
وَإِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى
سِهِمْ ۚ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوْا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُوْلُوْا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا
عَنْ هَذَا غَافِلِيْنَ
یعنی ” اس وقت کو یاد رکھو کہ جب تیرے رب نے بنی آدم کی پشت سے اُن کی ہونے
والی نسلوں کو مخاطب کر کے اور اُن کو خود ان کے متعلق گواہ رکھ کر فرمایا.کیا میں تمہارا رب
نہیں ہوں؟ اس پر انہوں نے جواب دیا.ہاں.بیشک تو ہمارا رب ہے.یہ اس لئے کیا
گیا کہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکو کہ ہم تو اپنے خدا کی ہستی کے متعلق غافل ہی
رہے.سورة الشمس - آیت 9
سورة الاعراف آیت 173
سورة البلد - آیت 11
119
Page 120
الغرض ہر انسان کی فطرت کے اندر نیکی بدی کا شعور پایا جاتا ہے اور یہ اس بات
کا ثبوت ہے کہ انسان خود اپنے آپ سے نہیں ہے اور نہ وہ کسی اندھے قانون کا نتیجہ ہے
اور یہ ایک ایسی روشن دلیل خدا کی ہستی کی ہے کہ جس سے کوئی عقلمند انکار نہیں کر سکتا.قبولیت عامہ کی دلیل
اس کے بعد جو دلیل میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ قبولیت عامہ کی دلیل ہے اور یہ
دلیل اس اصول پر مبنی ہے کہ دنیا میں کسی خیال یا عقیدہ کی عالمگیر مقبولیت جو ہر زمانہ میں
قائم رہی ہو اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ خیال یا عقیدہ اپنے اصل کے لحاظ سے حق و راستی
پر مبنی ہے.چنانچہ قرآن شریف فرماتا ہے:
فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ۚ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُتُ فِى الْأَرْضِ
یعنی ” جو چیز لوگوں کے واسطے حقیقی طور پر مفید اور نفع بخش ہوتی ہے وہی دُنیا میں
مستقل طور پر قائم رہتی ہے اور فضول اور بے نفع چیز کو یہ ثبات کبھی حاصل نہیں ہوتا.“
اسی طرح سائنس کا ایک اصل ہے جسے انگریزی میں سروائیول آف دی فٹسٹ
(Survival of the fittest) کہتے ہیں.جس کے یہ معنے ہیں کہ زندگی کی جنگ
میں وہی چیز سلامت رہتی ہے جو زیادہ مفید اور قائم رہنے کی زیادہ اہل ہوتی ہے اور
دوسری چیزیں جو اس کے مقابل میں ہوتی ہیں مٹ جاتی ہیں اور ہمارا مشاہدہ بھی ہمیں
یہی بتاتا ہے کہ دُنیا میں حقیقی اور دائمی ثبات صرف نفع بخش چیز کو حاصل ہوتا ہے اور ایک
ضرر رساں باطل یا غیر مفید چیز کبھی بھی مستقل اور عالمگیر فروغ حاصل نہیں کر سکتی.میرا یہ
مطلب نہیں کہ کوئی باطل یا غیر مفید چیز دنیا میں قائم ہی نہیں ہوسکتی بلکہ مطلب یہ ہے کہ
ایسی چیز کا قیام دائمی اور عالمگیر نہیں ہوسکتا بلکہ عارضی اور محدود ہوتا ہے.120
سورة الرعد آیت 18
↓
Page 121
اب اس اصل کے ماتحت ہم سوال زیر بحث پر نظر ڈالتے ہیں تو ایمان باللہ کا
عقیدہ ایک ایسا عقیدہ ثابت ہوتا ہے جس سے کسی عقلمند انسان کو انکار نہیں ہوسکتا.دنیا
ں جتنی بھی تو میں آباد ہیں خواہ وہ بڑی ہیں یا چھوٹی، متمدن ہیں یا غیر متمدن،
تعلیم یافتہ ہیں یا جاہل.غرض جتنی بھی قومیں ہیں اور جہاں بھی ہیں وہ باوجود اپنے بے
شمار اختلافات کے اس بات میں متفق ہیں کہ دُنیا و مافیها خود بخود اپنے آپ سے نہیں
ہے بلکہ اس کا کوئی خالق و مالک ہے اور یہ خیال صرف اس زمانہ کی اقوام تک ہی محدود
نہیں بلکہ جس جس زمانہ کی بھی تاریخ ہمارے سامنے محفوظ ہے اس میں بلا استثناء یہی
منظر نظر آتا ہے کہ کوئی قوم بھی اس عقیدہ سے خالی نہیں کہ یہ دنیا کسی بالا ہستی کی مخلوق
مملوک ہے.اس بالا ہستی کی صفات میں اختلاف ہے اور کافی اختلاف ہے.کوئی قوم
خدا کو کسی صورت اور کسی شکل میں پیش کرتی ہے تو کوئی کسی میں.پھر کوئی قوم خدا کو ایک
مانتی ہے اور اس کے نیچے یا اوپر کسی دوسرے معبود کی قائل نہیں تو کسی نے بہت سے
بڑے اور چھوٹے معبود بنا رکھے ہیں اور ان سب کے سامنے کم و بیش عبودیت کا خراج
پیش کرنے پر مصر ہے.غرض خدا کی ذات وصفات کے متعلق مختلف اقوام میں بہت بڑا
اختلاف پایا جاتا ہے.لیکن باوجود اس اختلاف کے تمام اقوام کے دین و مذہب کا
مرکزی نقطہ یہی نظر آتا ہے کہ یہ دنیا و مافیہا خود بخود نہیں بلکہ کسی بالا ہستی کی قدرت نمائی
کا کرشمہ ہے.کیا یہودی اور کیا عیسائی.کیا ہندو اور کیا مسلمان.کیا سکھ اور کیا پارسی.کیا
جینی اور کیا بدھ.پھر کیا شمالی امریکہ کے ریڈ انڈین اور کیا جنوبی افریقہ کے ہاٹن ٹاٹ
اور ز دلو.کیا مغربی افریقہ کے حبشی اور کیا آسٹریلیا کے وحشی.کیا منطقہ منجمدہ کے اسکیمو
اور کیا نیوزی لینڈ کے میوری.کیا ہندوستان کے گونڈ اور سنتھال اور کیا چین کے ٹوئی.پھر اگر زمانہ کے لحاظ سے نظر ڈالیں تو کیا موجودہ زمانہ کی دُنیا اور کیا غیر تاریخی زمانہ کے
لوگ.کیا وسطی زمانہ کی اقوام اور کیا ابتدائی زمانہ کے قبائل.غرض جس قوم اور جس زمانہ
121
Page 122
کولیں، یہ عقیدہ کسی نہ کسی صورت میں خواہ وہ مخفی ہو یا ظاہر ضرور ہمارے سامنے آتا ہے
کہ یہ دنیا کسی بالا ہستی کے قبضہ تصرف میں ہے.پس باوجود اس قدر عظیم الشان اور
كثير التعداد اختلافات کے تمام اقوامِ عالم کا ہر زمانہ میں اس بات پر متفق نظر آنا کہ اس
دُنیا کا کوئی خدا ہے قطع نظر اس کے کہ اس کی کیا صفات ہیں یا وہ ایک ہے یا زیادہ ہیں،
خدا تعالیٰ کے وجود پر ایک ایسی دلیل ہے جس سے کوئی عقلمند انکار نہیں کر سکتا.میں یہ
نہیں کہتا کہ یہ قو میں اس بات کا دعویٰ رکھتی ہیں کہ ہم نے خدا کو دیکھایا پہچانا ہے اور اس
کی صفات کا مشاہدہ کیا ہے اور گویا اس معاملہ میں اپنی عینی شہادت کو پیش کرتی ہیں بلکہ
میں صرف یہ کہتا ہوں
کہ تمام اقوامِ عالم باوجود اپنے بیشمار مذہبی اختلافات کے ہر زمانہ
میں خدا تعالیٰ کی ذات پر کسی نہ کسی صورت میں ایمان لانے کا دعوئی رکھتی رہی ہیں اور یہ
مجرد دعوی ہی اپنی عالمگیر مقبولیت کی وجہ سے اس بات کی دلیل ہے کہ واقعی کوئی خدا
ہے.خوب سوچ لوکسی عقیدہ کو اس قدر مقبولیت حاصل ہو جانا کہ وہ تمام دُنیا کا عقیدہ
بن جائے اور تمام قومیں اس کو اپنے دین و مذہب کا مرکزی نقطہ قرار دیں اور جب سے
کہ دُنیا کی تاریخ محفوظ ہے آج کے زمانہ تک کوئی ایک مثال بھی ایسی نظر نہ آئے کہ کوئی
قوم بحیثیت قوم ہونے کے اس عقیدہ سے قطعی طور پر منکر ہوئی ہو اس عقیدہ کے صحیح
ہونے پر ایک ایسی دلیل ہے جس سے انکار نہیں کیا جاسکتا.بیشک دُنیا میں غلط عقائد بھی
قائم ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات ان غلط عقائد کا حلقہ کرمانی اور مکانی طور پر کسی قدر
وسعت بھی حاصل کر لیتا ہے لیکن ایسا کبھی نہیں نظر آئے گا کہ کوئی غلط عقیدہ تمام دنیا
کے
گوشہ گوشہ میں قائم ہو گیا ہوتی کہ کوئی ایک قوم بھی اس سے مستثنی نظر نہ آتی ہو اور پھر وہ
کسی ایک زمانہ تک محدود نہ رہا ہو بلکہ جب سے دُنیا بنی ہوا سے یہی عالمگیر مقبولیت
حاصل چلی آئی ہو.اگر ایسا ہو تو دُنیا سے امان اُٹھ جائے اور حق و باطل میں امتیاز مشکل
122
Page 123
ہو جائے.پس اس عقیدہ کی کہ اس دُنیا کے اوپر کوئی بالا ہستی ہے یہ عظیم الشان مقبولیت
جو ہر قسم کے قیود زمانی اور مکانی سے آزاد ہے اور یہ شاندار ثبات جو تاریخ عالم میں اپنی
نظیر نہیں رکھتا اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ عقیدہ جھوٹانہیں ہوسکتا.اور اگر کوئی شخص یہ کہے کہ دُنیا میں ایسے لوگ بھی تو ہوتے رہے ہیں اور ہوتے
رہتے ہیں جو قطعاً کسی خدا کے قائل نہیں ہوتے.تو اس کا جواب یہ ہے کہ بے شک ہر
زمانہ میں ایسے لوگوں کا وجود پایا جاتا رہا ہے لیکن ان لوگوں کو کبھی کسی زمانہ میں بھی مستقل
طور پر قومی حیثیت حاصل نہیں ہوئی اور دہریت کا وجود کبھی بھی کسی قوم میں قومی عقیدہ
کے طور پر بالاستقلال قائم نہیں ہوا اور نہ کبھی دہریت کا سلسلہ دُنیا میں ایک مستقل اور
مستحکم سلسلہ کے طور پر جاری ہوا ہے اور اس سے زیادہ وقعت اس عقیدہ کو کبھی حاصل
نہیں ہوئی کہ چند آدمیوں کے دل و دماغ پر اس کی ایک عارضی حکومت قائم ہو جائے
اور بس.اقوامِ عالم کی تاریخ میں اس عقیدہ کی حیثیت ایسی ہی ہے جیسا کہ کسی ملک کی
منظم اور قائم شدہ سلطنت کے سامنے چند ایسے باغیوں کی حیثیت ہوتی ہے جو گا ہے
گا ہے بغاوت کا جھنڈا بلند کرتے رہتے ہیں مگر کبھی بھی ایک لمبے عرصہ کے لئے جتھہ
بنا کر حکومت کے سامنے کھڑے نہیں رہ سکتے اور نہ کبھی کسی معتد بہ علاقہ پر ان کو کوئی
مستقل اور مستحکم اقتدار حاصل ہوتا ہے کیا اس قسم کے باغیوں کی وجہ سے ملک کی قائم
شدہ حکومت میں کوئی شبہ کیا جاسکتا ہے؟ ہرگز نہیں.ہر گز نہیں.کیا خُدا کا عقیدہ تو ہم پرستی کا نتیجہ ہے؟
اس جگہ اگر کسی کو یہ شبہ گذرے کہ بعض مغربی مصنفین نے لکھا ہے کہ دُنیا میں
بعض قو میں ایسی بھی گذری ہیں جو بحیثیت قوم خدا کے عقیدہ سے بے بہرہ رہی ہیں تو
اس کا جواب یہ ہے کہ بیشک بعض مصنفین نے ایسا لکھا ہے اور خصوصاً ابتدائی زمانہ کے
123
Page 124
متعلق ان لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بعض قو میں خدا کے عقیدہ سے بے بہرہ نظر آتی ہیں
لیکن اگر غور سے مطالعہ کیا جائے تو صاف نظر آتا ہے کہ ان مصنفین کو دھوکا لگا ہے اور
انہوں نے پوری تحقیق سے کام نہیں لیا اور خصوصاً اُن
کو یہ غلطی لگی ہے کہ انہوں نے بعض
قدیم مشرک قوموں کے مشرکانہ عقائد کو محض خوف اور جہالت اور توہم پرستی کی طرف
منسوب کر دیا ہے اور غلط طور پر یہ سمجھ لیا ہے کہ خدائے واحد کا عقیدہ کبھی بھی ان کے اندر
پایا نہیں گیا.حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے اور حق یہ ہے کہ شرک کا عقیدہ گو وہ جہالت
کا نتیجہ ہی ہوتا ہے مگر وہ یقیناً خدا کے عقیدہ کی ایک فرع ہے نہ کہ اصل.یعنی مشرکانہ
عقائد ہمیشہ ایمان باللہ کی بگڑی ہوئی حالت کے نتیجہ میں پیدا ہوتے ہیں اور ایسا نہیں
ہوتا کہ خدا کا عقیدہ بالکل مفقود ہونے کی صورت میں بھی شرک کے عقائد پیدا
ہو جائیں.چنانچہ تاریخ عالم میں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ ایک قوم پہلے خدا کے
عقیدے پر قائم نظر آتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ اس میں مشرکانہ خیالات کا دخل شروع
ہو جاتا ہے اور بعض اوقات ان مشرکانہ عقائد کا ایسا غلبہ ہو جاتا ہے کہ خدا کا عقیدہ
پس پشت ڈالا جا کر آہستہ آہستہ بالکل نظروں سے اوجھل اور بالآخر مفقود ہو جاتا ہے.پس جب ایسی مثالیں موجود ہیں تو انصاف کا یہ تقاضا ہے کہ اوائل زمانہ کی جن اقوام میں
ہمیں سوائے مشرکانہ عقائد کے اور کچھ نظر نہیں آتا اور ان کی ابتدائی تاریخ بھی ہمارے
محفوظ نہیں ہے تو ان کے متعلق ہم یہی قیاس کریں کہ ابتداء وہ خدا کے عقیدہ پر قائم
ہونگی لیکن آہستہ آہستہ خُدا کا عقیدہ بالکل مفقود ہو گیا اور اس کی جگہ خالصتاً مشرکانہ
خیالات قائم ہو گئے.دراصل جو مثالیں بعض لوگوں نے ہمارے اس خیال کے خلاف
پیش کی ہیں وہ سب ایسی اقوام کی ہیں جن کی ابتدائی تاریخ محفوظ نہیں ہے.اور جب
ابتدائی تاریخ محفوظ نہیں ہے تو دوسرے واضح نظائر کو نظر انداز کر کے یہ خیال کر لینا کہ وہ
قو میں ابتداء سے ہی مشرکانہ خیالات پر قائم رہی ہیں اور یہ کہ ان کے مشرکانہ عقائد محض
پاس
124
Page 125
جہالت اور خوف اور تو ہم پرستی کا نتیجہ ہیں اور خدائے واحد کا عقیدہ ان کے اندر کبھی بھی
قائم نہیں ہو ، ایک بالکل غیر منصفانہ استدلال ہے جسے کوئی غیر متعصب دانا شخص قبول
نہیں کر سکتا.علاوہ ازیں اگر نظر غور سے دیکھا جائے تو صاف پہ لگتا ہے کہ مشرکانہ عقائد کبھی
بھی محض جہالت اور خوف اور تو ہم پرستی کے نتیجہ میں پیدا نہیں ہو سکتے بلکہ اس کے لئے
خدا کا عقیدہ پہلے موجود ہونا ضروری ہے.بے شک یہ ایک فطری تقاضا ہے کہ جب
ایک شخص کسی ایسی چیز کو دیکھتا ہے جو اس سے زیادہ طاقتور یا زیادہ مہیب یا زیادہ شاندار
یا زیادہ نفع رساں ہوتی ہے تو وہ اُس کے سامنے مرعوب ہو جاتا ہے اور اس کو ایک بڑی
چیز سمجھنے لگ جاتا ہے اور اس کے سامنے دیتا اور خائف رہتا ہے لیکن اگر ایسا شخص
عبودیت کے تصور سے بالکل نا آشنا ہے تو یہ بات قطعانا ممکن ہے کہ وہ محض اس رُعب یا
خوف کی وجہ سے اس کو اپنا معبود بنالے اور اس کو اپنا خالق و مالک سمجھنے لگ جائے.معبودیت کا خیال بہر حال اس بات کا متقاضی ہے کہ خیال کرنے والے شخص کے دماغ
میں اس سے پہلے کوئی تصور معبودیت کا موجود ہو.خوب سوچ لو کہ انسانی تصور کبھی بھی
کسی خیال
کا خالق نہیں بن سکتا ہاں البتہ نقال ضرور بن جاتا ہے.یعنی اگر کسی انسان
نے پہلے کوئی چیز دیکھی ہو یا سنی ہو یا وہ اس کے تجربہ میں آئی ہو تو تب ضرور اس شخص کا
تصور اس کے ذہن کے سامنے اس چیز کا نقشہ پیدا کر سکتا ہے اور پھر وہ اس نقشہ کو اپنے
تصور میں بڑھا اور پھیلا بھی سکتا ہے.لیکن اگر کسی نے کوئی چیز کبھی دیکھی یا سنی ہی نہ ہو
اور نہ ہی اس کی کوئی مثال اس کے سامنے آئی ہو تو اس صورت میں اس کا تصور ہر گز اس
کا نقشہ اس کے ذہن میں پیدا نہیں کر سکتا.پس جب ہر قوم کے عقائد میں کسی نہ کسی
صورت میں عابد و معبود کا مفہوم پایا جاتا ہے تو لا محالہ اس بات کو تسلیم کرنا پڑیگا کہ ہر قوم
اپنے اصل کے لحاظ سے خدا کے عقیدہ کو قبول کرتی ہے.وهو المراد
125
Page 126
اور اگر کسی کو یہ خیال گذرے کہ اس مضمون کے شروع میں تو بڑے زور وشور کے
ساتھ ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ آجکل دنیا میں اکثر لوگ خدا پر ایمان نہیں لاتے اور ہر قوم
دہریت کا شکار ہو رہی ہے مگر یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ تمام اقوامِ عالم خدا پر ایمان لاتی ہیں
اور یہ کہ یہ قبولیت عامہ دہریت کو بھی نصیب نہیں ہوتی.گویا ان دونوں بیانوں میں تضاد
ہے تو یہ شبہ قلت تدبر کا نتیجہ ہوگا.کیونکہ جہاں یہ کہا گیا ہے کہ آجکل سب قو میں دہریت
کا شکار ہورہی ہیں وہاں حقیقی ایمان کو مد نظر رکھا گیا ہے لیکن موجودہ بحث میں صرف
عقیدہ کے ایمان یعنی غیر حقیقی ایمان کا ذکر ہے.پس یہ دونوں بیان متضاد نہیں کہلا سکتے
کیونکہ دونوں اپنی اپنی جگہ بچے ہیں.یہ بھی سچ ہے کہ اس زمانہ میں دُنیا کے اکثر لوگ
خدا پر ایمان نہیں لاتے کیونکہ جس قسم کا ایمان اُن کے اندر پایا جاتا ہے وہ کوئی زندہ
حقیقت نہیں ہے جو عملاً اُن کی زندگیوں پر اثر پیدا کر سکے اور یہ بھی سچ ہے کہ دُنیا کی
ساری قو میں خدا پر ایمان لاتی رہی ہیں کیونکہ گوان کا ایمان کیسا ہی کمزور اور مُردہ بلکہ
مشرکانہ ہو اس میں شک نہیں کہ وہ بحیثیت قوم عقیدہ ہمیشہ کسی نہ کسی صورت میں اس
ایمان پر قائم رہی ہیں کہ اس دُنیا کے اوپر کوئی خدا ہے جس کے قبضہ تصرف میں ہماری
جانیں ہیں.اور ظاہر ہے کہ اس جگہ صرف عقیدہ کے ایمان کا ذکر ہے باطنی حقیقت کی
بحث نہیں.پس دونوں بیان اپنی اپنی جگہ سچے ہوئے اور تضاد کوئی نہ رہا.خلاصہ کلام یہ
کہ وہ عظیم الشان اور عالمگیر مقبولیت جو ایمان باللہ کے عقیدہ کو ہر زمانہ میں حاصل رہی
ہے اس بات کی دلیل ہے کہ یہ عقیدہ حق و راستی پر مبنی ہے اور اس کے مقابل کا عقیدہ جو
دہریت کے نام سے موسوم ہوتا ہے غلط اور باطل ہے.وھو المراد
یقین کے تین درجے
اگلی دلیل جو میں ہستی باری تعالیٰ کے متعلق بیان کرنا چاہتا ہوں وہ بھی گو عقلی
126
Page 127
ہے اور خدا کے متعلق ہونا چاہیے والے مرتبہ سے تعلق رکھتی ہے لیکن اہل بصیرت اس
سے خدا تعالیٰ کی ذات کی طرف ایک یقینی اور قطعی اشارہ پاسکتے ہیں.دراصل یہ نہ سمجھنا
چاہئے کہ عقلی دلائل محض شکی دلائل ہیں اور ان سے کوئی مرتبہ یقین کا ذات باری تعالیٰ
کے متعلق پیدا نہیں ہو سکتا.جو شخص یہ سمجھا ہے وہ بالکل غلط سمجھا ہے کیونکہ خدا کے متعلق
ہونا چاہیے“ کا مرتبہ بھی ایک یقین کا مرتبہ ہے جس طرح کہ ” ہے“ کا مرتبہ ایک
یقین کا مرتبہ ہے.فرق صرف یہ ہے کہ ”ہونا چاہئے“ کے مرتبہ میں وہ یقین کامل
حاصل نہیں ہوسکتا جو ہے“ کے مرتبہ میں حاصل ہوتا ہے اور وہ اطمینان اور تسکین کی
صورت نہیں ہوتی جو ہے“ کے مقام پر پہنچ کر حاصل ہوتی ہے ورنہ وہ بھی ایک یقین کا
وو
وو
مقام ہے جس میں عقلمند آدمی کے واسطے کسی قسم کے انکار کی گنجائش نہیں ہوتی.دراصل یقین کے مختلف مراتب ہیں.ایک یقین وہ ہے جو کسی چیز کے متعلق عقلی
دلائل کے نتیجہ میں پیدا ہوتا ہے اور آثار کو دیکھ کر کسی چیز کے وجود پر دلیل پکڑی جاتی
ہے.مثلاً ہم دُور سے ایک جنگل میں آگ کا دھواں اٹھتا دیکھتے ہیں اور اس سے یہ
استدلال کرتے ہیں کہ یہاں ضرور کوئی آگ ہوگی جس سے یہ دھواں اُٹھتا ہے کیونکہ
اس
قسم کا دھواں بغیر آگ کے نہیں ہوسکتا اور ہمارا یہ استدلال ہم میں اس آگ کے وجود
کے متعلق ایک عقلی یقین پیدا کر دیتا ہے.اس قسم کا یقین قرآن شریف کی اصطلاح میں
علم الیقین“ کہلاتا ہے.یعنی وہ یقین جو کسی علمی یا عقلی استدلال کے نتیجہ میں پیدا ہوا
ہو اور جس میں براہ راست مشاہدہ کا دخل نہ ہو اور ظاہر ہے کہ ” ہونا چاہیئے“ کا مرتبہ بھی
اسی قسم کے یقین کا مرتبہ ہے کیونکہ اس میں بھی آثار سے (نہ کہ براہ راست رویت
سے ) ذات باری تعالیٰ کے وجود پر دلیل پکڑی جاتی ہے.مگر جب ہم آگ کو اپنی
آنکھوں سے دیکھ لیتے یا اُس کی مخصوص صفت سوزش کا عملاً تجربہ کر لیتے ہیں تو پھر یہ
ہونا چاہیئے والا یقین ہے والے پختہ اور قطعی یقین میں بدل جاتا ہے.دوسرے
وو
127
Page 128
وو
الفاظ میں ” ہونا چاہئے“ اور ” ہے“ کے مرتبوں میں جو فرق ہے اس کو اس طرح ظاہر
کر سکتے ہیں کہ ” ہونا چاہئے“ والے مرتبہ میں تو ہم خدا کی ذات پر دلائل کی مدد سے
ایمان لاتے ہیں اور ” ہے“ والے مرتبہ میں دلائل کا واسطہ نہیں رہتا بلکہ گویا مشاہدہ کا
رنگ پیدا ہو جاتا ہے.اس موقعہ پر یقین کے باقی دو درجوں کا ذکر کر دینا بھی خالی از فائدہ نہ ہوگا جو
قرآن شریف نے بیان فرمائے ہیں.پہلا مرتبہ جس کا ذکر اوپر گذر چکا ہے
علم الیقین“ کا مرتبہ ہے اور یہ بتایا جا چکا ہے کہ یہ وہ مرتبہ ہے کہ جس میں آثار سے
علمی استدلال کے طور پر کسی چیز کے متعلق یقین حاصل کیا جاتا ہے.دوسرا مرتبہ
عین الیقین“ کا مرتبہ ہے اس میں استدلال کا واسطہ نہیں رہتا بلکہ مشاہدہ کی ابتداء
شروع ہو جاتی ہے.مثلاً وہی آگ والی مثال لے کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم اس
دھوئیں کی سمت میں چلتے چلتے آخر آگ کی روشنی کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا شروع
کر دیتے ہیں تو پھر ہمیں اس کے متعلق صرف ” علم الیقین نہیں رہتا بلکہ عین الیقین“
حاصل ہو جاتا ہے.یعنی ایسا یقین حاصل ہو جاتا ہے جو براہِ راست رؤیت سے پیدا
ہوتا ہے اور اس میں استدلال کا دخل نہیں ہوتا.اس مرتبہ کے اوپر ایک تیسرا مرتبہ بھی ہے جسے قرآن شریف کی اصطلاح میں
حق الیقین“ کہتے ہیں.یہ مقام انسان کو تب حاصل ہوتا ہے کہ جب وہ آگ سے اتنا
قریب ہو جاتا ہے کہ اس کی گرمی کو محسوس کرنے لگ جاتا ہے.بالفاظ دیگر آگ کے اس
طبعی اور ممتاز خاصہ کو جوگرمی کے نام سے موسوم ہے خود اپنے نفس میں محسوس کرنا شروع
کر دیتا ہے.اور دوسری طرف وہ آگ کی روشنی کو صرف دیکھتا ہی نہیں بلکہ قرب کی
وجہ سے اس کی تپش سے فائدہ بھی اُٹھاتا ہے اور اس کی روشنی کے ذریعہ صحیح اور غلط راستے
میں امتیاز بھی کر سکتا ہے.یہ وہ انتہائی مرتبہ یقین کا ہے جس کے اوپر کوئی اور مرتبہ نہیں.128
Page 129
ہاں بیشک خود اس انتہائی مرتبہ کے اندر مختلف ما تحت مراتب کا وجود ضرور پایا جاتا ہے اور
ہر شخص اپنی استعداد اور جدو جہد کے مطابق یقین کا مرتبہ حاصل کرتا ہے، لیکن اس جگہ
اس تفصیل میں پڑنے کی ضرورت نہیں.الغرض یقین کے مختلف مراتب ہیں اور ” ہونا
چاہئے“ والا مرتبہ جس کے متعلق اس وقت ہم بحث کر رہے ہیں ان مراتب میں سے
ابتدائی مرتبہ ہے جسے ” علم الیقین کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے.غلبہ رُسل کی دلیل
ہستی باری تعالیٰ کی وہ دلیل جومیں اب پیش کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ جب سے
دُنیا کی تاریخ محفوظ ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب کبھی بھی خدا پر ایمان لانے والوں اور
خدا کا انکار کرنے والوں کا (خواہ وہ انکار عقیدہ کا ہو یا ملی ) مقابلہ ہوا ہے غلبہ ہمیشہ
ایمان لانے والوں کے ساتھ رہا ہے.جس سے پتہ لگتا ہے کہ ایمان لانے والوں کی
نصرت میں کوئی غیبی ہاتھ کام کرتا ہے.میرا یہ مطلب نہیں کہ ہر قسم کے اختلاف میں
مومن بہر حال کافر کے خلاف فتح پاتا ہے کیونکہ عام حالات میں فتح و شکست قانون نیچر
کے ماتحت آتی جاتی ہے اور کوئی وجہ نہیں کہ اگر ایک کافر کامیابی کے طریق کو اختیار کرتا
ہے اور ایک مومن نہیں کرتا تو کافر کو فتح نصیب نہ ہو اور مومن کو ہو جائے.عام حالات
میں ایسا کبھی نہیں ہوگا بلکہ کامیابی اسی کا حصہ رہے گی جو کامیابی کے رستے پر چلتا ہے
خواہ وہ کوئی ہو.پس اس جگہ دنیا کے عام اختلافات اور مقابلے میرے مد نظر نہیں بلکہ
مراد یہ ہے کہ جب کبھی بھی کوئی راستباز شخص اس دعوئی کے ساتھ دنیا میں کھڑا ہوتا ہے
کہ خدا کی طرف سے میری زندگی کا یہ مشن مقرر کیا گیا ہے کہ میں ایمان کو دُنیا میں قائم
کروں تو پھر وہ ضرور اپنے مشن میں کامیاب ہو کر رہتا ہے اور دُنیا کی کوئی طاقت اس کی
کامیابی کے رستہ میں روک نہیں ہوسکتی.چنانچہ قرآن شریف فرماتا ہے:.129
Page 130
كَتَبَ اللهُ لَا غُلِبَنَّ اَنَا وَرُسُلِي
یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ مقدر کر رکھا ہے کہ وہ اور اُس کے رسول ہمیشہ غالب رہیں گے.چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک رسول اکیلا اُٹھتا ہے اور مادی اسباب کے لحاظ سے
بھی گویا بالکل بے سروسامان ہوتا ہے اور اُس کے مخالفین اپنی تعداد کے لحاظ سے اور
اپنے سامانوں کے لحاظ سے بظاہر ایسے نظر آتے ہیں کہ بس ایک آن کی آن میں اُسے
کچل کر رکھ دینگے لیکن پھر بھی اس کی فولادی میخیں آہستہ آہستہ لوگوں کے قلوب میں
دهستی چلی جاتی ہیں اور محمدی کا سہرا آخر اسی کے سر پر بندھتا ہے اور اس کے مخالف
ذلیل وخوار ہو کر اپنا سامنہ لے کر رہ جاتے ہیں.یہ نظارہ دُنیا نے ایک دفعہ نہیں دیکھا،
دو دفعہ نہیں دیکھا، دس ہیں دفعہ نہیں دیکھا، سو پچاس دفعہ نہیں دیکھا، بلکہ ہزاروں دفعہ
دیکھا ہے.اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ دنیا کی تاریخ میں ایک مثال بھی ایسی نہیں ملتی کہ
اس قسم کے مقابلے میں دہریہ کو (دہریہ سے مراد اس جگہ ہر وہ شخص ہے جو یا تو خدا کا
بالکل ہی منکر ہے اور یا صرف رسمی طور پر خدا پر ایمان لاتا ہے اور حقیقتا ایمان باللہ پر قائم
نہیں ) فتح نصیب ہوئی ہو.میرے عزیز و ! خوب غور کرو.ایک جنگ ہے جو دنیا کے مختلف حصوں میں مختلف
قوموں میں مختلف زمانوں میں مختلف حالات میں دس میں دفعہ نہیں ، چالیس پچاس دفعہ
نہیں سینکڑوں دفعہ نہیں، ہزاروں دفعہ پیش آتی ہے اور ہر دفعہ ایک طرف خدا کا ایک
بے یارو مددگار ، بے سروسامان بندہ ہوتا ہے جو خدا کا نام لے کر کھڑا ہوتا ہے اور دوسری
طرف منکرین کا عظیم الشان لاؤلشکر ہر قسم کے سازوسامان سے آراستہ ڈیرے ڈالے ہوتا
ہے.مگر جب جنگ شروع ہوتی ہے تو آخر میدان اسی خدا کے بندے کے ہاتھ رہتا ہے
اور دہریت کی فوج کو اسیر ہو کر اس کے حلقہ بگوشوں میں شامل ہونا پڑتا ہے.کیا یہ سب کچھ
سورة المجادلة آيت 22
130
Page 131
اتفاق کا نتیجہ ہے؟ بھلا کوئی ایک مثال تو دو کہ اس
قسم کی جنگ میں منکرین کی فوج نے فتح
پائی ہو اور خدا کے بندے کو ذلت کا منہ دیکھنا پڑا ہو.کیا یہ نظارہ اس بات کا یقینی ثبوت نہیں
کہ خدا کا نام لے کر کھڑے ہونے والوں
کی مدد میں ایک قادر المطلق ہستی کا ہاتھ کام کرتا
ہے جس کے مقابل میں دُنیا کے ساز و سامان ایک مُردہ کیڑے کی بھی حیثیت نہیں رکھتے.آریہ ورت کے میدانوں میں حضرت کرشن اور رام چندر جی کے کارناموں کو
دیکھو.یہ بزرگ لوگ کس آواز کے ساتھ دُنیا میں اُٹھے اور ہندوستان کے نمک حرام
فرزندوں نے اُن کے ساتھ کیا سلوک کیا ؟ مگر آخر نتیجہ کیا نکلا؟ کیا آج آریہ ورت کی
گردنیں ان مقدس ہستیوں کے سامنے جھک جھک کر اپنی غلامی کا اقرار نہیں کر رہیں؟
ابوالانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے حالات زندگی پر نظر ڈالو.یہ خدا کا بندہ
اکیلا تن تنہا شام کی تاریک وادیوں میں خدا کا نام لے کر کھڑا ہوتا ہے اور دہریت کے
بہادر سپوت اس آواز پر اس کو جلتی ہوئی آگ کے منہ میں جھونک دیتے ہیں.مگر وہ
بظاہر بے یار و مددگار انسان ڈرتا نہیں خوف نہیں کھاتا بلکہ اس طرح تکبیر کے راگ گاتا
چلا جاتا ہے جیسے کوئی پھولوں کی سیج پر آرام سے لیٹا ہوا ہو.ایسا کیوں ہوا؟ اس لئے کہ
حضرت ابراہیم کے کانوں میں کسی بالا ہستی کی یہ آواز گونج رہی تھی کہ اے ابراہیم
آسمان کی طرف دیکھ.کیا تو ان ستاروں کو گن سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم عرض کرتے
ہیں.اے میرے آقا! تیرے لشکر کو کون شمار کر سکتا ہے؟ ارشاد ہوتا ہے ابراہیم ! تو
نے ہم سے محبت و وفا کا عہد باندھا ہے اب ہمیں بھی اپنی ذات کی قسم ہے کہ تیری آل
و اولا د بھی اسی طرح آسمان ہدایت کے ستارے بنکر چمکے گی اور گنی نہیں جائے گی.دیکھ
لو.آج دنیا میں جتنے حضرت ابراہیم کے نام لیوا موجود ہیں وہ کسی اور نبی کو میسر نہیں مگر
حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالنے والے کہاں ہیں؟
پھر حضرت موسیٰ کو لے لو.ایک غریب خاندان میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے
131
Page 132
جسے اس کے گھر والے فرعون کے ڈر سے صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دیتے
ہیں.فرعون کے لوگ اُسے دریا سے اُٹھا لیتے ہیں اور رحم کے طور پر یا کسی اور خیال سے
فرعون اسے اپنے گھر میں پالے جانے کا حکم دیتا ہے.یہ لڑکا جب بڑا ہوتا ہے تو سلطنت
کے ایک جرم کی سزا سے خائف ہو کر وطن سے بھاگ نکلتا ہے اور جنگلوں کی خاک
جھانتے ہوئے آخر ایک نیک انسان کی خدمت اختیار کرتا ہے.جہاں دس سالہ خدمت
کے بعد اس کی شادی ہوتی ہے اور پھر وہ خدائی نُور سے منور ہو کر فرعون کے دربار کی
طرف واپس آتا ہے اور سر دربار کھڑے ہو کر فرعون کے منہ پر کہتا ہے کہ ” میں اُس خدا
کا اینچی ہوں جو تیرا اور میر اسب کا خالق و مالک ہے میرے ساتھ بنی اسرائیل کو روانہ کر
دو ورنہ انجام ٹھیک نہیں ہوگا.فرعون حکومت کے نشے میں مخمور ہے تیوری چڑھا کر
جواب دیتا ہے کہ ” اے موسیٰ! کیا تو میرے سامنے اس طرح بولتا ہے.ہاں تو جو
میرے گھر کے ٹکڑوں پر پلا ہے ذرا ہوش میں آ کر بات کر.“ حضرت موسی سمجھ جاتے
ہیں کہ اس بدمست دیو کا خمار یوں اُتر تا نظر نہیں آتا.تجویز ہوتی ہے کہ کسی حکمت عملی
سے خفیہ طور پر بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر نکل چلیں پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا.فرعون کو
علم ہوتا ہے تو غیظ و غضب میں آپے سے باہر ہو ا جاتا ہے اور حکومت کے جرارلشکر کو
ساتھ لے کر اُن جنگل میں بھاگ نکلنے والوں کا تعاقب کرتا ہے اور بس دیکھتے ہی دیکھتے
اُن کو جالیتا ہے.بنو اسرائیل جن کو برسوں کی غلامی نے نامردوں سے بدتر بنارکھا تھا یہ
نظارہ دیکھ کر سہمے جاتے ہیں.اُن کے عقب میں فرعون کا جرار شکر ہے اور سامنے مہیب
سمندر ہے.گھبرا کر حضرت موسیٰ سے کہتے ہیں کہ موسیٰ ! اب کیا ہوگا ؟ مگر حضرت موسیٰ
ہیں کہ چٹان کی طرح قائم ہیں.ان سہمے ہوئے چہروں پر نظر ڈال کر فرماتے ہیں: گلا
إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِيْنِ یعنی ” خبردارگھبرانے کی کوئی بات نہیں میرے ساتھ میرا
ے "
سورة الشعراء - آیت 63
132
Page 133
خدا ہے.دیکھو وہ ابھی ہمارے لئے رستہ بنائے دیتا ہے.اللہ اللہ ! یہ وہی حضرت موسیٰ
ہیں جو آج سے چند برس پہلے مصر کی پولیس سے ڈر کر وطن سے بھاگ نکلے تھے.اب
فرعون کا لاؤلشکر سامنے ہے اور حضرت موسیٰ“ کے ماتھے پر بل تک نہیں آتا! پھر نتیجہ کیا
ہوتا ہے؟ حضرت موسی کے لئے سمندر پھٹ کر راستہ بنا دیتا ہے مگر فرعون مع اپنے لشکر
اور ساز وسامان کے سمندر کی مہیب موجوں کا شکار ہو جاتا ہے.پھر اسی پر بس نہیں بلکہ
آج حضرت ابراہیم کی طرح حضرت موسیٰ" کے نام لیوا بھی شمار سے باہر ہیں اور فرعون
کو کوئی جانتا تک نہیں البتہ اس کا مردہ جسم لوگوں
کی عبر نگاہ بنا ہو ا.ا ہے.آؤاب حضرت مسیح ناصری کا نظارہ کریں.بنو اسرائیل کی ایک غریب بے بیاہی
لڑکی کے گھر میں لڑکا پیدا ہوتا ہے.بد باطن یہود چہ میگوئیاں کرتے ہیں کہ لڑکی تو بھی
بیا ہی نہیں گئی یہ لڑکا کہاں سے آگیا؟ اور اس بات کو بُھول جاتے ہیں کہ پیدائش ایک
سابقہ پیشگوئی کے مطابق تھی.لے اور اس بات کو بھی بھول جاتے ہیں کہ میچ کی کم از کم
ماں تو موجود ہے.حضرت آدم کا تو ان کے خیال کے مطابق نہ باپ تھا نہ ماں.خیر یہ
بے باپ کا لڑکا بڑا ہوتا ہے اور پھر روح القدس کی تائید پا کر وہی پرانی آواز بلند کرتا ہے
جو حضرت کرشن نے ہندوستان میں اور حضرت ابراہیم نے شام میں اور حضرت موسیٰ"
نے مصر میں بلند کی تھی مگر یہود جو پہلے سے ہی اُسے سج آنکھوں سے دیکھ رہے تھے
غیظ و غضب سے بھر جاتے ہیں اور آخر نوبت یہاں تک پہنچتی ہے کہ یہود کی سازش سے
میچ کو صلیب پر لٹکا دیا جاتا ہے اور یہود خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے میدان مارلیا.لیکن
مسیح کے پیچھے کسی او کا ہاتھ تھا.وہ اپنے نام لیوا کی مدد کو آتا ہے اور اُسے اس ذلت کی
موت کے مونہہ سے نکال لیتا ہے اور اپنے محبت کے کلام سے اُسے یوں تسلی دیتا ہے
کہ ” آج میری ایک مصلحت سے یہود نے تجھ پر ایک عارضی تسلط پایا ہے.لیکن
یسعیاہ باب 7 آیت 14
133
Page 134
میں تیر وفادار آقا ہوں اب قیامت تک یہ یہود تیرے حلقہ بگوشوں کے پاؤں کے نیچے
رہیں گے.اور دُنیا دیکھ لے گی کہ دراصل تو نے فتح پائی ہے نہ کہ ان یہود نے “ آج
دُنیا کیا نظارہ دیکھتی ہے؟ کیا مسیح کے خادم ساری دنیا پر ایک سیل عظیم کی طرح نہیں
چھار ہے؟ اور یہود کا کیا حال ہے؟ وہی یہود جو ایک دن مسیح کے سر پر کانٹوں کا تاج
رکھتے تھے اور تمسخر کے ساتھ کہتے تھے کہ دیکھو یہ ہمارا بادشاہ ہے آج مسیح کے خادم رحم
کھا کر اُن کے سروں پر ارضِ مقدس کی بادشاہت کا تاج رکھنا چاہتے ہیں مگر کوئی رکھنے
نہیں دیتا اور آج تک بنی اسرائیل کی ساری قوم سیخ کو صرف چند گھنٹوں کے لئے سولی پر
لٹکانے کی وجہ سے گویا اُنیس سو سال سے خود سولی پر ٹکی ہوئی ہے.اللہ اللہ ! خدا کی بھی
کیسی عبرتناک پکڑ ہے.پھر سب کے سردار محمد مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم (فداہ نفسی ) کے وجود باجود کی
طرف نگاہ کرو.قریش کے ایک معز زمگر غریب گھرانے کے لڑکے کی شادی ایک
حیا پر ورلڑکی سے ہوتی ہے.خاوند اور بیوی بہت تھوڑا عرصہ اکٹھا رہنا پاتے ہیں کہ اس
لڑکی کے سر سے خاوند کا سایہ اُٹھ جاتا ہے.وہ لڑکی اس وقت حمل سے ہے اور اُس کے
پیٹ کا بچہ اس کے خاوند کی یاد کو اس کے معصوم دل میں اور بھی زیادہ دردناک طور پر تازہ
رکھ رہا ہے.خیر وہ بچہ پیدا ہوتا ہے.ماں اُسے دیکھتی ہے اور گو اس وقت اُس کے مرحوم
خاوند کی یاد زیادہ در دوالم کے ساتھ اس کے دل میں تازہ ہو رہی ہے مگر وہ خوش بھی ہے
کہ اس کے خاوند کے نام کو زندہ رکھنے والا بچہ اب اُس کی آنکھوں کے سامنے ہے.وہ
اُسے قریش کی رسم کے مطابق کسی بدوی دایہ کے سپر د کرنا چاہتی ہے.مگر یتیم بچے کو کون
لے؟ آخر بڑی تلاش کے بعد ایک دایہ ملتی ہے جو بچے کو اپنے ساتھ لے جانے پر
رضامند ہو جاتی ہے اور اس طرح یہ نبیوں کا سرتاج عرب کے صحرائی جھونپڑوں میں اپنی
زندگی کے ابتدائی دن گزارتا ہے.جب عمر ذرا بڑی ہوتی ہے تو یہ بچہ اپنی ماں کے پاس
134
Page 135
واپس آجاتا ہے.مگر زیادہ عرصہ نہیں گذرتا کہ ماں بھی عالم ارواح میں اپنے مرحوم خاوند
سے جاملتی ہے اور یہ بچہ بغیر ماں باپ کے رہ جاتا ہے.اس کے بعد بعض رشتہ داروں کی
آغوش تربیت میں یہ بچہ جوان ہوتا ہے اور بڑا ہو کر دوسرے قریش کی طرح تجارت کے
کاروبار میں مصروف ہو جاتا ہے اور اسی حالت میں اس کی عمر کے سال گذرتے جاتے
ہیں.وہ بالکل ان پڑھ اور اُمتی ہے مگر اپنے اخلاق فاضلہ سے قریش میں خاص عزت
کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور لوگ اُسے ”امین“ کے لقب سے پکارتے ہیں.جب
اُس کی عمر چالیس سال کے قریب ہوتی ہے تو اُس کی طبیعت خلوت گزینی کی طرف مائل
ہو جاتی ہے اور قریش کے عادات و رسوم اور اُن کا مذہب اس کی سلیم فطرت کو
قابل نفرت نظر آتے ہیں.وہ ایک اعلیٰ ضابطہ اخلاق اور دل کو سچی تسکین دینے والے
مذہب کی تلاش میں سرگردان رہتا ہے.مکہ کے پاس ایک ویران پہاڑ ہے جس میں
ایک ویران غار ہے.یہ جگہ اُسے اپنی خلوت نشینی کے لئے پسند آتی ہے اور وہ دن رات
اُسی کے اندر بیٹھا رہتا ہے اور ایک نامعلوم ہستی کی یاد میں جو اُس کے بے چین دل کو
تسکین دے سکے اپنا وقت گزارتا ہے.اس کا کوئی راز دار نہیں ہے مگر اس کی بوڑھی
بیوی جو مکہ میں رہتی ہے اور اپنے خاوند کو پریشان دیکھ کر خود پر یشان ہوئی جارہی ہے.اسی طرح وقت گذرتا جاتا ہے اور آخر وہ وقت آتا ہے کہ اس نامعلوم ہستی کی ضیاء پاش
کر نیں جس کی تلاش میں وہ سرگردان ہے اس کے قلب صافی پر گرنی شروع ہوتی ہیں
اور عالم روحانی کا وسیع منظر اُس کی نیم باز آنکھوں کے سامنے گھلنا شروع ہوتا ہے.پھر مختصر یہ کہ زیادہ عرصہ نہیں گذرتا کہ وہ اس پردہ مستوریت سے باہر آ کر اپنے
خُدا داد منصب کو قریش کے سامنے پیش کرتا ہے اور ان کو اُس خُدا کی طرف بلا تا ہے جو
اس دُنیا کا خالق و مالک ہے اور جس کے بغیر اور کوئی خدا نہیں.سردارانِ قریش اُس کی
اس بات کو سُن کر ہنس دیتے ہیں اور اُسے قابل التفات نہیں سمجھتے.مگر وہ اپنے کام میں
135
Page 136
لگا رہتا ہے اور آخر چند سمجھدار وفا شعار لوگ اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں اور اُس کی
باتوں پر ایمان لاکر اس کے کام میں ہاتھ بٹانے لگتے ہیں.اب اُس کی قوم کی بھی
آنکھیں کھلتی ہیں اور وہ
ہیں اور وہ یہ محسوس کرنے لگتی ہے کہ یہ آواز صرف ہنس کر ٹال
دینے والی نہیں بلکہ اگر اس کی روک تھام نہ کی گئی تو یہ آواز ان کی قوم میں پھوٹ اور
جتھہ بندی پیدا کر دیگی.اور اب سے اس عظیم الشان اور تاریخ عالم میں بے نظیر مذہبی
جنگ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے جس نے بیس سال تک عرب کے وسیع ملک میں ایک زلزلہ
اور طوفان برپا کر رکھا اور ملک کے ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک ایک ایسی
آگ لگادی جو اُس وقت تک نہیں بجھی جب تک کہ سارا ملک ایک واحد خُدا کے
جھنڈے کے نیچے جمع نہیں ہو گیا.سب سے پہلے قریش مکہ نے مسلمانوں کی اس میٹھی
بھر جماعت کو جبراً اُن کے پُرانے دین کی طرف لوٹانا چاہا اور اُن کو ایسے ایسے مظالم کا
تخیہ مشق بنایا جن کا حال پڑھ کر بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں.بلال ایک حبشی
غلام تھے اُن کے کانوں میں اسلام کی آواز پڑی تو فطرتِ صحیحہ نے فوراً قبول کر لیا.اُن کا
آقا امیہ بن خلف قریش کا ایک بڑار کیس تھا.اُس بدبخت نے اُن کو اتنے دُکھ دیئے کہ
خدا کی پناہ.دوپہر کے وقت جبکہ اوپر سے آگ برستی تھی اور ملکہ کا پتھر یلا میدان بھٹی کی
طرح پیتا تھا اُمیہ بن خلف ان کو باہر لے جاتا اور اُن کو ننگا کر کے ریت پر لٹا دیتا اور
بڑے بڑے گرم پھر اُن کے سینے پر رکھ کر خود او پر چڑھ بیٹھتا اور کہتا.” محمد سے الگ
ہو جا اور خدا کی پرستش ترک کر دے اور بتوں کے سامنے سجدہ کر ورنہ اسی طرح عذاب
دے دے کر مار دونگا.بلال زیادہ عربی نہیں جانتے تھے.آسمان کی طرف دیکھتے اور
کہتے.احد - احد.یعنی ” خُدا ایک ہے خدا ایک ہے میں اسے نہیں چھوڑ سکتا.“ پھر یہ
ظالم ان کو رشی سے باندھ کر شریر لڑکوں کے حوالے کر دیتا اور وہ ان کو ملتے کی پتھریلی گلی
کوچوں میں گھسیٹتے پھرتے جس سے اُن کا نگا بدن زخمی ہوکر خون سے تر بہ تر ہو جاتا اور
136
Page 137
امیہ پھر اُن سے پوچھتا کہ بلال ! اب بتا کیا کہتا ہے؟ بلال کے منہ سے پھر وہی آواز
نکلتی کہ احد - احد یعنی ” خدا ایک ہے خدا ایک ہے.اور ظالم لڑکے پھر اُمیہ کا اشارہ
پا کر اُن کو گرم پتھروں پر گھسیٹنا شروع کر دیتے.ایک اور مسلمان تھے جن کا نام خباب
تھا.یہ غلام نہ تھے بلکہ آزاد تھے اور مکہ میں لوہاری کی دوکان کرتے تھے.قریش کے
شریر نو جوانوں نے غصہ میں آکر اُن کو اُن کی بھٹی کے دہکتے ہوئے کوئلوں کے اوپر لٹا دیا
اور ایک شخص ان کی چھاتی پر چڑھ بیٹھا تا کہ وہ کروٹ نہ بدل سکیں حتی کہ وہ کو نئے اسی
طرح جل جل کر اُن کی پیٹھ کے نیچے ٹھنڈے ہو گئے مگر اس وفادار بندہ نے خدا کا دامن
نہ چھوڑا.سمیہ ایک غریب مسلمان عورت تھی.ابوجہل نے ان پر زور ڈالا کہ اسلام سے
تو بہ کر لو ورنہ سخت عذاب دے دے کر مار دونگا مگر اُس خدا کی بندی نے نہ مانا اور اسلام
پر قائم رہی.آخر اس بد باطن نے ان کی شرمگاہ میں نیزہ مار کر انہیں مکہ کے پتے ہوئے
میدان میں شہید کر دیا.یہ اس مذہبی جنگ کے ابتدائی کارناموں کی چند مثالیں ہیں جو
قریش مکہ کی طرف سے غریب اور بیکس مسلمانوں کے خلاف وقوع میں آئے.خود مسلمانوں کے آقا اور سردار فداہ نفسی ) پر طائف کے شریر لوگوں نے پتھر
برساد یئے کشتی کہ آپ کا بدن سر سے لیکر پاؤں تک زخموں سے چھلنی ہو گیا اور آپ کے
خون سے آپ کی جوتیاں بھر گئیں اور خود مکہ کے اندر آپ کا بائیکاٹ کر کے آپ کو
ہلاک کرنے کی کوشش کی گئی.آخر جب یہ مظالم انتہا کو پہنچ گئے اور بالآ خر قریش نے یہ
فیصلہ کر لیا کہ خواہ کچھ ہو محمد صلعم کو جان سے ماردینا چاہئے تا کہ اس سلسلہ کا خاتمہ ہوتو
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم معہ اپنے چند ساتھیوں کے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے
گئے تا کہ شائد اسی طرح قریش کا غصہ فرو ہو جائے اور وہ مسلمانوں کو امن کے ساتھ
زندگی بسر کرنے دیں اور اُن کی پُر امن تبلیغ میں روک نہ ہو.مگر اس بات نے قریش کی
آتش غضب کو اور بھی بھڑ کا دیا اور اُن کے رُؤ سانے سارے ملک میں چکر لگا لگا کر تمام
137
Page 138
قبائل عرب کو مسلمانوں کے خلاف اکسانا شروع کر دیائی کہ مسلمانوں کی ایسی حالت
ہوگئی کہ جس طرح ایک شخص ایسے جنگل میں گھر جائے جس کے چاروں طرف صد ہا
میل تک آگ کے شعلے بلند ہورہے ہوں.چنانچہ ذیل کی تاریخی روایت مسلمانوں کی
اُس وقت کی حالت کا نقشہ پیش کرتی ہے.تاریخ میں آتا ہے:
” جب محمد صلتم اور ان کے اصحاب مدینہ میں آئے اور مدینہ کے بعض لوگوں نے اُن کو
پناہ دی تو سارا عرب ایک جان ہو کر اُن کے خلاف اُٹھ کھڑا ہوا.اس وقت مسلمانوں کی
یہ حالت تھی کہ رات کو ہتھیار لگا لگا کر سوتے تھے اور دن کو بھی ہر وقت ہتھیار لگائے
پھرتے تھے اس خیال سے کہ نمعلوم کب کوئی دشمن اُن پر حملہ آور ہو جائے اور گھبر اگھبرا کر
کہتے تھے کہ دیکھئے ہمیں وہ دن دیکھنے کب نصیب ہوتے ہیں کہ جب ہم امن اور
اطمینان کا سانس لے سکیں گے اور سوائے خدا کے ہمیں کسی اور کا ڈر نہیں رہے گا.“ لے
اُس وقت مسلمانوں کی تعداد چند گنتی کے آدمیوں سے زیادہ نہ تھی.اور وہ بھی
عموماً حد درجہ غریب اور کمزور اور بے سروسامان تھے.اور دوسری طرف اُن کے مقابل
میں سارے ملک
کی متحدہ طاقتیں اپنے بے انداز سرو سامان سے جمع ہو کر ایک سیل عظیم
کی طرح اُٹڈی چلی آتی تھیں تا کہ اس مٹھی بھر جماعت کو جو خدا کا نام لے کر کھڑی ہوئی
ہے ہمیشہ کے لئے صفحہ دُنیا سے مٹادیں.اس بے نظیر جنگ میں جو جو قربانیاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے
صحابہ کو کرنی پڑیں اور جن جن مشکلات میں سے گذرنا پڑا وہ ہر سیخ تاریخ میں مذکور ہیں
اس جگہ اُن کے اعادہ کی ضرورت نہیں.مگر ایک واقعہ ایسا ہے کہ جسے میں اس جگہ
نظر انداز نہیں کر سکتا.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑی جماعت کے ساتھ حجاز کی
ایک وادی میں سے گزر رہے تھے کہ اچانک سامنے سے ایک دشمن قبیلہ نے تیروں کی
لباب النقول في اسباب النزول
138
Page 139
ایک باڑ ماری اور مسلمانوں کے حلیف اس غیر متوقع حملہ سے گھبرا کر پیچھے ہے.بس پھر
کیا تھا ساری اسلامی فوج میں کھلبلی مچ گئی اور اونٹ گھوڑے نیچرمیں گدھے مع اپنے
سواروں کے منہ موڑ کر بے تحاشہ بھاگ نکلے.دشمن نے یہ نظارہ دیکھا تو شیروں کی
طرح گر جتا ہوا آگے بڑھا اور بھاگتے ہوئے مسلمانوں پر تیروں
کا مینہ برسانا شروع کر
دیا.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اردگر دنظر ڈالی تو میدان صاف پایا.نہ مکہ
کے جدید نومسلم نظر آتے ہیں نہ مدینہ کے وفاشعار انصار اور نہ پرانے رفقاء،مہا جر.اور
اگر کوئی نظر آتا ہے تو صرف دشمن ہے جو ایک طوفانِ عظیم کی طرح سامنے سے
انڈا چلا آتا
ہے اور تیروں کی بارش ہے کہ الامان ! مگر آپ ایک پہاڑ کی طرح اپنی جگہ پر قائم رہتے
ہیں اور نہایت اطمینان کے ساتھ اپنے ایک سہمے ہوئے ساتھی سے جو پاس کھڑا ہو انظر
آتا ہے، فرماتے ہیں کہ ذرا میرے گھوڑے کی لگام مضبوطی سے تھام لو تا کہ یہ تیروں
سے گھبرا کر پیچھے کی طرف منہ نہ موڑے اور پھر اپنے گھوڑے کو زور کے ساتھ ایڑ لگا کر یہ
للکارتے ہوئے دشمن کی طرف آگے بڑھتے ہیں کہ :.انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب
یعنی ” میں اللہ کا نبی ہوں جھوٹا نہیں ہوں“.نمعلوم اس آواز میں کیا جادو بھرا تھا کہ جن جن مسلمانوں کے کانوں تک یہ آواز
پہنچی وہ گرتے پڑتے مارتے کاٹتے پھر اپنے آقا کے گرد جمع ہو جاتے ہیں اور آن کی آن
میں دشمن کی بڑھتی ہوئی صفوں کو بکھیر کر رکھ دیتے ہیں.الغرض یہ جنگ ہوئی اور غار حرا
کے اس خلوت پسند گوشہ گزین کو مدینہ میں پناہ لئے ابھی نو سال کا عرصہ نہ گذرا تھا کہ
عرب کا وسیع ملک جو نو لاکھ مربع میل کے رقبہ پر مشتمل ہے ایک سرے سے لے کر
دوسرے سرے تک تکبیر کے نعروں سے گونجنے لگ گیا.کوئی کہے گا یہ تلوار کا کھیل ہے.میں کہتا ہوں تم بھی ایسا کھیل کر کے دکھا دو.139
Page 140
ایک اکیلا شخص غریب
و ناتواں شخص کمزور و بے سروسامان شخص اٹھتا ہے اور چند سال
کے عرصہ میں ملک کی کایا پلٹ کر رکھ دیتا ہے اور ملک بھی وہ جو سر سے لیکر ایڑی تک اس
کے خلاف ہتھیار بند تھا.کیا یہ تلوار کا کھیل ہے یا خُدائے غیور کی قدرت نمائی کا کرشمہ؟
نادانو تلوار کس نے اُٹھائی؟ کیا تم میں سے کوئی ہے جو یہ ثابت کر سکے کہ تلوار کے
اُٹھانے میں مسلمانوں نے ابتداء کی تھی ؟ پھر کیا تم میں سے کوئی ہے جو یہ ثابت کر سکے
کہ جب مسلمانوں نے خود حفاظتی اور قیام امن کے لئے تلوار اٹھائی تو اُس وقت بھی
انہوں نے کسی ایک فرد واحد کو تلوار سے ڈراگر مسلمان بنایا ہو؟ اے تاریکی کے بدقسمت
فرزند و! میں تمہیں کس طرح یہ یقین دلاؤں کہ عرب نے خود مسلمانوں کے خلاف تلوار
اُٹھائی اور اُس نے صرف اس وقت اپنی تلوار واپس اپنی نیام میں ڈالی جب اُس نے یہ
سمجھ لیا کہ محمد صلعم کے پیچھے کسی ایسی طاقتور ہستی کا ہاتھ ہے جس کے سامنے دُنیا
کے
ساز وسامان ایک پر پیشہ کی بھی حقیقت نہیں رکھتے.پس بیشک انہوں نے ڈر کر اسلام
قبول کیا لیکن تلوار سے ڈر کر نہیں بلکہ خُدا سے ڈر کر.اور بے شک انہوں نے اپنے
ہاتھ سے اپنے بتوں کو توڑا لیکن مسلمانوں کی طاقت کا خوف کھا کر نہیں بلکہ خود ان بتوں
کو ذلیل اور بے بس پا کر.چنانچہ تاریخ سے پتہ لگتا ہے کہ جب فتح مکہ کے موقعہ پر
مشرکوں کے بت توڑے گئے تو مکہ کے بعض رئیس اُن بتوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے
ہوئے کہتے تھے کہ:.اگر ان بتوں میں کچھ بھی طاقت ہوتی تو آج عرب کی متکبر گردنیں محمد کے
سامنے نہ جھکتیں
وہ لوگ جن کے ساتھ یہ ساری کہانی گذری ہے خود اپنے منہ سے تو یہ کہیں اور تم
تیرہ سوسال بعد آنے والے عرب کے ملک سے ہزاروں میل پر رہتے ہوئے اسلامی
تاريخ الخميس
140
Page 141
تاریخ سے جاہل مطلق یہ کہو کہ عرب نے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم ) کی تلوار سے ڈر کر اسلام
قبول کیا تھا! تعصب کا ستیاناس ہو.بے انصافی کی بھی کوئی حد ہونی چاہئے.الغرض آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بے نظیر کامیابی اس بات کا ایک بین
ثبوت ہے کہ آپ کی نصرت میں ایک طاقتور ہستی کام کر رہی تھی اور وہ وہی ہے جسے ہم
خدا کہتے ہیں.اور اب بھی جبکہ آپ کی وفات پر ساڑھے تیرہ سو سال گذر چکا ہے
حلقہ
چالیس کروڑ انسان آپ کی غلامی کو اپنے لئے فخر کا موجب سمجھتا ہے.اور یہ
دن بدن وسیع ہوتا جاتا ہے اور خدا کے فضل سے وہ وقت دور نہیں کہ عالم روحانی کا یہ
بے مثل تاجدار اپنے حسنِ خدا داد سے تمام دنیا کے قلوب پر حکومت کریگا اور اسود واحمر کی
گردنیں اس ظل اللہ کے سامنے محبت کی غلامی میں جھکیں گی.اللهم صلّ عليه واله
وسلّم وياايها الذين آمنوا صلّوا عليه وسلّموا تسليما.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم (فدا نفسی ) کے بعد آپ کے خادم اور ظلتِ کامل اور
بروز جمالی حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کی ذاتِ والا صفات بھی اسی
سلسلہ کی ایک مقدس کڑی ہے.ایک گمنام ریل و تار سے دُور پردہ تاریکی میں مستور
گاؤں کے اندر ایک بچہ پیدا ہوتا ہے.ماں باپ کے سایہ کے نیچے وہ بڑھتا ہے مگر
خلوت پسند طبیعت کی وجہ سے اپنے گاؤں کی محدود سوسائٹی سے بھی الگ الگ رہتا
ہے.باپ اپنی شفقت پدری کی وجہ سے کوشش کرتا ہے کہ کسی اچھی ملازمت پر اپنے
اس بچہ کو فائز کر دے اور اُسے پیغام بھیجتا ہے کہ فلاں اعلیٰ افسر میرے ساتھ خاص دوستی
کا تعلق رکھتا ہے اور وہ آجکل برسر اقتدار ہے چلو میں اُسے کہہ کر تمہارے واسطے معقول
ملازمت کا انتظام کرا دیتا ہوں.جواب آتا ہے کہ ” آپ میرے لئے فکر مند نہ ہوں
میں نے جہاں نو کر ہونا تھا، ہو چکا ہوں.یعنی میں خدا کی نوکری سے مشرف ہو چکا
ہوں.مجھے دُنیا کی نوکریوں کی ضرورت نہیں.اور اب سے اس مقدس نوکری کی
141
Page 142
داستان شروع ہوتی ہے جس نے آج مذہبی دنیا میں گویا ایک زلزلہ اور طوفان برپا کر رکھا
ہے.حضرت مرزا صاحب علیہ السلام نے 1884ء میں مجددیت کا دعویٰ دُنیا کے
سامنے پیش کیا.مگر چونکہ اس دعوی میں کوئی ایسی بات نہ تھی جو مسلمانوں کو خاص طور پر
چونکانے کا موجب ہوتی کیونکہ اسلام میں بہت سے مجد دظاہر ہو چکے ہیں.اس لئے
عموماً اسلامی دنیا نے اس دعویٰ کو خاموش قبولیت یا کم از کم عدم انکار کی نظر سے دیکھا اور
حضرت مرزا صاحب علیہ السلام بدستور اپنے منصب خداداد کے مطابق اسلام کی تائید
میں مصروف رہے اور سمجھدار مسلمان آپ کی ان خدمات کو شکر و امتنان کی نظر سے دیکھتے
رہے کیونکہ وہ آپ کی خدمات کی وجہ سے محسوس کرتے تھے کہ اگر آج مسلمانوں کے
اندر کوئی شخص اس بات کی اہلیت رکھتا ہے کہ مخالفین کے مقابلہ میں عزت اور کامیابی
کے ساتھ عہدہ برآ ہو سکے تو وہ صرف آپ ہی ہیں.مگر حضرت مرزا صاحب علیہ السلام
کی ان خدمات نے مخالفین اسلام یعنی ہندوؤں اور عیسائیوں کے اندر عداوت و دشمنی
کی ایک خطر ناک آگ مشتعل کر دی اور انہوں نے ہر ممکن طریق سے آپ کو نقصان
پہنچانے اور نیچا دکھانے کی ٹھان لی.لیکن ابھی اس حالت پر زیادہ عرصہ نہ گذرا تھا کہ
حضرت مرزا صاحب علیہ السلام نے خدا تعالیٰ سے حکم پا کر اپنا یہ دعویٰ شائع کیا کہ آخری
زمانہ کے متعلق مسیح کے نزول اور مہدی کے ظہور کی جو پیشگوئی تھی اس کا مصداق میں
ہوں اور حضرت مسیح ناصری علیہ السلام جن کی دوبارہ آمد کا انتظار کیا جارہا ہے فوت
ہو چکے ہیں.بلکہ آپ نے یہ بھی دعوئی فرمایا کہ دُنیا کے مختلف مذاہب میں جو آخری
زمانہ کے متعلق پیشگوئیاں پائی جاتی ہیں کہ اس زمانہ میں ایک عظیم الشان مصلح کا ظہور
ہوگا جو باطل کا مقابلہ کر کے اُسے مغلوب کر دیگا اور اس کے ہاتھ پر حق و صداقت کی فتح
ہوگی وہ سب میری ذات میں پوری ہوئی ہیں اور میں ہی وہ موعود ہوں جس کا جملہ ادیان
142
Page 143
میں وعدہ دیا گیا تھا اور جس کے ہاتھ پر اسلام کی آخری اور عالمگیر فتح مقدر ہے.اس دعوی نے جو طوفان بے تمیزی مخالفت کا برپا کیا اور جس طرح تمام مذاہب
ایک جان ہو کر آپ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے وہ اپنی نظیر آپ ہی ہے.کیا دوسرے
مسلمان اور کیا عیسائی کیا ہندو اور کیا آریہ اور کیا جینی اور کیا سکھ.پھر کیا برہمو اور کیا
دیوسماجی وغیرہ وغیرہ سب کے سب اپنے پورے زور کے ساتھ آپ کے خلاف ہاں
ایک اکیلے اور بے سروسامان شخص کے خلاف میدان میں اُتر آئے.اکثر مسلمان علماء
نے آپ
کو کا فر لحد ضال مضل، بلکہ دجال قرار دیا اور ایک با قاعدہ شرعی فتویٰ کے ذریعہ
تمام اسلامی دنیا میں یہ اعلان کر دیا کہ یہ شخص کا فر اور دائرہ اسلام سے خارج بلکہ اسلام کا
بدترین دشمن ہے.اور جو شخص اس کے ساتھ کسی قسم کا تعلق رکھے گا وہ بھی اسلام سے
خارج ہو جائے گا.اور یہ بھی شائع کیا گیا کہ اس شخص کو ہر ممکن طریق سے نقصان پہنچانا
نہ صرف جائز بلکہ کار ثواب ہے.اور بعض نے تو یہاں تک فتویٰ دیا کہ اسلامی شریعت
کی رُو سے یہ شخص واجب القتل ہے اور اس کے قتل کرنے والا ثواب کا حقدار ہے.اور
اس قولی مخالفت کے علاوہ جو اپنے اثر کے لحاظ سے محض قولی نہ تھی بلکہ ملک میں ایک
خطرناک آگ کے مشتعل کر دینے کا موجب ہوئی عملی طور پر بھی ہر جائز و نا جائز طریق
سے آپ کو مغلوب کرنے اور ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کی گئی.اور مسلمان، عیسائی،
ہندو وغیرہ سب اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ آپ پر حملہ آور ہو گئے.سلسلہ احمدیہ کی ابتدائی تاریخ ایک درد ناک کہانی ہے جس کے مطالعہ سے بدن
کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں.ایک طرف ایک اکیلا شخص ہے جس کے پاس بظاہر
حالات کوئی جتھہ نہیں، کوئی ساز وسامان نہیں، کوئی مال و دولت نہیں کوئی نام ونمود نہیں.دوسری طرف گویا دُنیا بھر کی افواج ہر ممکن ساز وسامان سے آراستہ ایک سیل عظیم کی
طرح چاروں طرف سے انڈی چلی آتی ہیں مگر وہ شخص ڈرتا نہیں، ہراساں نہیں ہوتا.143
Page 144
ایک مستحکم چٹان کی طرح اپنی جگہ پر قائم ہے.اس کے ہاتھ میں کوئی تلوار نہیں جسے
چلائے
، کوئی مال نہیں جسے بکھیرے، کوئی ظاہری علم نہیں جس کیسا تھ مرعوب کرے، کوئی
طاقت نہیں جس کے ساتھ ڈرائے.ہاں صرف ایک روحانی جھنڈا ہے جس پر کسی ایک
غیر ارضی روشنائی میں لکھے ہوئے یہ الفاظ چمک رہے ہیں کہ :
دُنیا میں ایک نذیر آیا پر دنیا نے اُس کو قبول نہ کیا لیکن خُدا اُسے قبول کرے گا اور بڑے
زور آور حملوں سے اُس کی سچائی ظاہر کر دے گا.اور جوں جوں دشمن کا حملہ خطر ناک صورت اختیار کرتا جاتا ہے توں توں وہ اس آسمانی
جھنڈے کو اپنے ہاتھوں میں بلند کرتا جاتا ہے.اور نہ معلوم ان الفاظ میں کیا جادو بھرا
ہے کہ منکرین کی افواج کے سپاہی ان الفاظ کو دیکھتے ہیں اور اپنی صفوں کو چھوڑ چھوڑ کر
اس جھنڈے کی طرف بھیجے چلے آتے ہیں.مخالف گروہ ان لوگوں کو ہر ممکن طریق سے
تنگ کرتا ہے، تمدنی سزائیں دیتا ہے، اُن کے مال و دولت کو چھین لیتا ہے، ان کے بیوی
بچوں کو اُن سے جدا کر دیتا ہے، ان کو مارتا ہے، پیٹتا ہے، قابو پاتا ہے تو قتل کر دینے سے
دریغ نہیں کرتا، ان کے مُردوں کو اپنے مقبروں میں دفن کرنے سے روکتا ہے مگر لوگ
ہیں کہ بے خود ہو کر کھچے چلے آتے ہیں اور اپنی ظاہری آزادی کے تخت سے اتر اتر کر
اس گاؤں کے رہنے والے بے یارومددگار بے نام و نمود شخص کی غلامی کا طوق اپنی
گردنوں میں پہننے کے واسطے بے چین ہوئے جاتے ہیں.↓
اللہ اللہ یہ کیا نظارہ ہے! مخالفین کہتے تھے کہ یہ ایک چھر ہے جو اپنی بھنبھناہٹ
سے ہمارے دماغ کو پریشان کر رہا ہے اگر یہ خاموش نہ ہو اتو ہم اسے اپنی انگلیوں میں
لیکر مسل دینگے.مگر آج اُسی ” بھنبھنانے والے“ کے نام لیوا دنیا کے ہر قلعہ پر حملہ آور
ہیں اور دشمن بھی اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اگر آج مذہبی دنیا میں کوئی طاقت ہے تو یہ
براہین احمدیہ حصہ چہارم مصنفہ 1884ء
144
Page 145
ہے.کیا یہ کسی انسانی ہاتھ کا کام ہے؟ ہرگز نہیں ہرگز نہیں.انسانی ہاتھ کا کام اسباب اور
ماحول کا محتاج ہوتا ہے مگر یہاں جتنے بھی اسباب تھے وہ دشمن کے ہاتھ میں تھے اور
حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ تھا.مگر باوجود مخالفوں کی انتہائی
کوششوں کے حضرت مرزا صاحب کی فولادی میخیں دُنیا کے قلوب میں دھستی ہی چلی
گئیں اور جب 1908ء میں آپ کو خدا کی طرف سے پیغامِ وصال آیا تو چار لاکھ
جاں نثار، وفا شعار خادم آپ کے جھنڈے کے نیچے جمع تھا اور اب جبکہ آپ کی وفات پر
صرف سترہ سال گذرے ہیں.آپ کے نام لیوا اسلام کی تبلیغ کے لئے دُنیا کے
ہر ملک میں پھیلے ہوئے نظر آتے ہیں اور خدا کے رستہ میں اپنی بے نظیر قربانیوں سے دنیا
کی نظروں کو حیرت میں ڈال رہے ہیں.یہ باتیں کوئی قصے کہانیاں نہیں بلکہ واقعات
ہیں جن کو دشمن بھی اپنی عداوت اور تعصب کے پردے میں نہیں چھپا سکتا.ایک گمنام
شخص گاؤں کا رہنے والا شخص بے سروسامان شخص اُٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ خدا نے مجھے
اپنے نام کا جلال قائم کرنے کے لئے کھڑا کیا ہے.دُنیا اس کا انکار کرتی ہے اور
ہر مذہب و ملت کے لوگ اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ اس کے خلاف میدان میں اُتر
آتے ہیں اور اپنی طاقت کے گھمنڈ میں متوالے ہو کر سمجھتے ہیں کہ بس ہم ایک آن کی
آن میں اسے صفحہ دنیا سے حرف غلط کی طرح مٹا کر رکھ دینگے.اس وقت جدھر دیکھو
دشمن ہی دشمن ہیں اور دشمن بھی ایسے کہ بس خون کے پیاسے اور اس کے مقابلہ میں اپنے
سارے اختلافات کو بھول کر ایک جان ہو جانے والے اور اُن میں سے ہر ایک اس
بات کا شائق ہے کہ سب سے پہلے وہی آگے بڑھ کر اپنا وار کرے مگر وہ جس کو یہ لوگ
ایک بھنبھنانے والا مچھر یا ایک پانی کا بلبلہ سمجھتے تھے وہ خدائے غیور کے ہاتھ میں
ایک ایسی بر ہنہ تلوار تھی کہ وہ جس پر گری اُسے ہلاک کیا اور اُس پر جو گرا وہ ہلاک ہوا.ایڈیشن ثانی کے وقت ارتمیں سال گزر چکے تھے اور ایڈیشن سوم کے وقت سینتالیس سال
145
Page 146
بڑے بڑے بہادر اس جری اللہ کے سامنے آئے مگر جس طرح بھٹی میں دانے بھنتے
ہوئے چھٹتے ہیں اس طرح دیکھتے دیکھتے اُڑ گئے.آخر یہ کیوں ہوا؟ سلسلہ احمدیہ کی ابتدائی حالت کی طرف دیکھو اور پھر اس
مخالفت کی طرف نگاہ کرو جو اس کے سامنے آئی اور پھر اُس کی موجودہ حالت کا مطالعہ کرو
اور پھر انصاف سے کہو کہ کیا یہ خارق عادت
کا میابی بغیر کسی غیبی نصرت و تائید کے ممکن
تھی؟ ایک اکیلا بے سروسامان شخص خدا کا نام لے کر اُٹھتا ہے اور باوجود دنیا بھر کی
شدید ترین مخالفت کے تئیں چالیس سال کے قلیل عرصہ کے اندر چارا کناف عالم میں
اپنا تسلط اس طرح جما لیتا ہے کہ جیسے گویا مذہبی دُنیا میں بس اسی کی حکومت ہے.ہندوستان میں احمدیوں کا مشن ہے.سیلون میں احمدیوں کا مشن ہے شام میں احمدیوں کا
مشن.ں ہے.فلسطین میں احمدیوں کا مشن ہے.لبنان میں احمدیوں کا مشن ہے.ایران
میں احمدیوں کا مشن ہے.انگلستان میں احمدیوں کا مشن ہے.جرمنی میں احمدیوں کا
مشن ہے.ہالینڈ میں احمدیوں کا مشن ہے.سوئٹزر لینڈ میں احمدیوں کا مشن ہے.اٹلی
میں احمدیوں کا مشن ہے.سپین میں احمدیوں کا مشن ہے.ٹرینڈاڈ میں احمدیوں کا مشن
ہے.شمالی امریکہ میں احمدیوں کا مشن ہے.جنوبی امریکہ میں احمدیوں کا مشن ہے
مشرقی افریقہ میں احمدیوں کا مشن ہے.مغربی افریقہ میں احمدیوں کا مشن ہے.ماریشس میں احمدیوں کا مشن ہے.ملایا میں احمدیوں کا مشن ہے.جاوا میں احمدیوں کا
مشن ہے.سماٹرا میں احمدیوں کا مشن ہے.بور نیو میں احمدیوں کا مشن ہے.اور یہ
مشن سسکتے ہوئے جان توڑتے ہوئے دشمن کے حملوں سے مغلوب مشن نہیں بلکہ اپنی
اپنی جگہ ایک طاقت ہیں جن کا لوہا دُنیا مانتی ہے اور اے وہ شخص جو جماعت احمد یہ کونج
اب ایڈیشن سوم کے وقت جماعت احمدیہ کے تبلیغی مشنوں کی تعد اد اور بھی زیادہ ہو چکی ہے اور دنیا
کے بیشتر ممالک میں احمدی مبلغ پہنچ کر اسلام کی خدمت بجالا رہے ہیں.منہ
146
Page 147
آنکھوں سے دیکھتا اور اس حیرت انگیز تر قی پر غیظ وغضب میں آکر خون کے آنسو بہاتا
اور اپنی نادانی سے اسلام کی ترقی پر گڑھتا ہے سن رکھا ابھی تو.ابتدائے عشق ہے روتا
ہے کیا
آگے آگے دیکھیو ہوتا
ہے کیا
الغرض حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بانی سلسلہ احمدیہ اور آپ کی جماعت
کی کامیابی جن مخالف حالات میں اور جس سرعت کے ساتھ حیرت انگیز طور پر وقوع
میں آرہی ہے وہ اس بات کا ایک بین ثبوت ہے کہ کوئی غیبی طاقت جو دُنیا کی تمام
طاقتوں پر غالب اور حکمران ہے آپ کی تائید میں کام کر رہی ہے اور اسی کا نام ہم خُدا
رکھتے ہیں.خلاصہ کلام یہ کہ جب سے کہ اس دُنیا کی تاریخ محفوظ ہے ہمیشہ یہ نظارہ دُنیا کی
آنکھوں کے سامنے آتا رہا ہے کہ جب کبھی بھی کوئی راستباز خدا کی طرف سے حکم پا کر
خدا کے نام پر کھڑا ہوا ہے تو اُسے خواہ کیسے بھی حالات پیش آئے ہیں وہ بالآخر غالب
اور بامراد ہوکر رہا ہے اور اس کے دشمنوں کو باوجود اپنی گونا گوں طاقت اور بے انداز
ساز وسامان کے ہمیشہ ذلت کامنہ دیکھنا پڑا ہے اور یہ نظارہ جیسا کہ میں نے اوپر بیان کیا
ہے ایک دو دفعہ یا دس ہیں دفعہ دیکھنے میں نہیں آیا بلکہ ہزاروں دفعہ دیکھنے میں آیا ہے اور
دُنیا کی تاریخ میں کوئی ایک مثال بھی اس کے خلاف نظر نہیں آتی.پس یہ غلبہ اس بات
کا ایک یقینی اور قطعی ثبوت ہے کہ خدا کے نام پر کھڑا ہونے والوں کی تائید میں کوئی
زبر دست غیبی طاقت کام کرتی ہے جس کے مقابل میں دُنیا کے ساز و سامان ایک مُردہ
کیڑے کی بھی حقیقت نہیں رکھتے اور اسی کو ہم خدا کہتے ہیں جس کے آستانہ الوہیت پر
ابن آدم کا جبینِ نیازخم ہونا چاہئے.کاش لوگ سمجھیں.حضرت مرزا صاحب کیا خوب
فرماتے ہیں:
147
Page 148
قدرت سے
اپنی ذات کا دیتا ہے حق ثبوت
اُس بے نشاں کی چہرہ نمائی یہی تو
ہے
جس بات کو کہے کہ کروں گا میں یہ ضرور
ملتی نہیں وہ بات خُدائی یہی تو ہے
شہادت صالحین کی دلیل
آخری عقلی دلیل جو میں اس مضمون میں ہستی باری تعالیٰ کے متعلق بیان کرنا
چاہتا ہوں وہ شہادتِ صالحین سے تعلق رکھتی ہے.یعنی اس اصول پر مبنی ہے کہ بہت
سے ایسے لوگ جن کی راست گفتاری مسلم ہے اور اُن کے صحیح الدماغ ہونے میں بھی
کوئی کلام نہیں اس بات کی ذاتی شہادت پیش کرتے ہیں کہ واقعی ہمارا ایک خُدا ہے جسے
ہم نے اُسی طرح دیکھا اور پہچانا ہے جس طرح ہم دوسری غیر مرئی چیزوں کو دیکھتے اور
پہچانتے ہیں.ہر شخص جو تھوڑی بہت عقل اور تجربہ رکھتا ہے سمجھ سکتا ہے کہ حصول علم کے ذرائع
میں سے شہادت بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے بلکہ اگر ہم اپنے معلومات کے وسیع
میدان پر نظر ڈالیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہماری معلومات کا بیشتر حصہ ایسا ہے جو ہمیں
خود براہِ راست حاصل نہیں ہوا بلکہ دوسرے معتبر لوگوں کی روایت یا گتپ صحیحہ کے
مطالعہ یا اخبارات وغیرہ کے دیکھنے سے حاصل ہوا ہے اور ہمیں خود کبھی بھی اسے اپنے
ذاتی مشاہدہ یا تجربہ میں لانے کا موقعہ نہیں ملا.لیکن بایں ہمہ ہمیں ان معلومات کے
متعلق قریباً قریباً ایسا ہی پختہ یقین ہے جیسا کہ اپنے مشاہدہ یا تجربہ کے ذریعہ حاصل
شدہ معلومات کے متعلق ہے.اور کوئی وجہ نہیں کہ ایسا نہ ہو کیونکہ اگر ہم اپنے تجربہ اور
مشاہدہ پر یقین لاتے ہیں اور اُسے قابلِ اعتماد سمجھتے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ ایک دوسرے
148
Page 149
شخص کے مشاہدہ اور تجربہ کو جو ہماری طرح ہی دل و دماغ رکھتا ہے اور جس کی راست
گفتاری بھی شک وشبہ سے بالا ہے ہم قبول نہ کریں.اخبارات میں ہم دُنیا بھر کی خبر میں
پڑھتے ہیں اور اُن
کو صحیح مانتے ہیں.خواص الاشیاء کے متعلق جو جدید تحقیقا تیں ہورہی
ہیں اور جن سے دُنیا کے علوم میں گویا ایک نئے عالم کا دروازہ کھل رہا ہے انہیں ساری
دُنیا تسلیم کرتی ہے حالانکہ وہ لوگ جنہوں نے ان خواص کو اپنے ذاتی تجربہ کے ذریعہ
براہ راست محسوس کیا ہے بہت ہی تھوڑے ہیں.پھر تمام دنیا کی فوجداری اور دیوانی
عدالتوں کے فیصلہ جات زیادہ تر زبانی یا تحریری شہادتوں کے ذریعہ ہی سرانجام پاتے
ہیں اور کوئی اعتراض نہیں کرتا.تاریخ کا علم بہت بڑی حد تک لوگوں کی زبانی یا تحریری
شہادت پر مبنی ہے اور اسے سب تسلیم کرتے ہیں.جغرافیہ کے علم کو لوتو ہندوستان کا
بچہ بچہ یہ یقین رکھتا ہے کہ لنڈن ایک شہر ہے جو انگلستان کا دارالسلطنت ہے حالانکہ
ہندوستان کی آبادی کے ایک فیصدی حصہ نے بھی لنڈن کو نہیں دیکھا ہو گا مگر دوسروں کی
شہادت کی وجہ سے سب مانتے ہیں.اس کے علاوہ ہم عملاً اپنی روزمرہ کی زندگی میں
دیکھتے ہیں کہ بہت سی باتوں کو ہم صرف اس لئے مانتے ہیں کہ دوسرے لوگ اُن کے
متعلق شہادت دیتے ہیں حالانکہ ہمیں خود اُن کے متعلق کوئی ذاتی علم حاصل نہیں ہوتا.الغرض شہادت علم کے حصول کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے جس سے کوئی عقلمند انکار
نہیں کر سکتا کیونکہ اگر اس سے انکار کیا جائے تو بہت سے علوم دنیا کے بیشتر حصہ کے
واسطے باطل اور بے کار چلے جاتے ہیں کیونکہ شہادت کے اصول سے انکار کرنے کے یہ
معنے ہیں کہ لوگ صرف ان
باتوں کو مانیں جواُن کے ذاتی تجربہ اور مشاہدہ میں آچکی ہیں
اور باقی سب کا انکار کر دیں.بلکہ اگر غور سے دیکھیں تو شہادت کے اصل کا انکار کر کے
ہم کسی علم کے بھی قائل نہیں رہ سکتے کیونکہ اگر زید و بکر کا مشاہدہ اور تجربہ باوجود اس کے
کہ وہ راستباز اور صحیح الدماغ ہیں اور اُن کے واسطے غلط بیانی کا کوئی محرک بھی نہیں ہے،
149
Page 150
قابل تسلیم نہیں ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ ہمارا اپنا مشاہدہ اور تجر بہ خود ہمارے واسطے
قابل تسلیم ہو.اگر وہ اپنے مشاہدہ میں غلطی کر سکتے ہیں تو ہم بھی غلطی کے ارتکاب سے
بالا نہیں ہیں لہذا ثابت ہوا کہ شہادت کے اصل کا انکار کر کے سوائے اس کے کہ
تو ہم پرستی کا دروازہ کھول دیا جائے اور کوئی نتیجہ نہیں نکلتا.کوئی شخص کہ سکتا ہے کہ بعض اوقات شہادت غلط بھی ہوتی ہے اور بعض اوقات
گواہ دروغگو تو نہیں ہوتا لیکن بوجہ ناقص الفہم ہونے کے اُس کی شہادت قابلِ قبول نہیں
رہتی.یہ درست ہے اور ہم اسے تسلیم کرتے ہیں لیکن اس احتمال کی وجہ سے شہادت کا
دروازہ حصول علم کے واسطے ہرگز بند نہیں کیا جا سکتا.اگر کسی خراب اور بوسیدہ دوائی کے
استعمال سے کسی مریض کو نقصان پہنچ جائے تو کیا اس سے یہ نتیجہ نکالا جاسکتا ہے کہ وہ
دوائی اپنی ذات میں غیر مفید اور ضرر رساں ہے؟ اسی طرح جھوٹے اور ناقص الفہم شاہد
کی شہادت سے یہ نتیجہ ہرگز نہیں نکالا جاسکتا کہ شہادت کا اُصول ہی باطل ہے.اس
سے تو صرف یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جس طرح ایک خراب شدہ دوائی کے استعمال سے پر ہیز
لازم ہے اسی طرح ایک دروغگو یا نا قص الفہم شخص کی شہادت کے قبول کرنے میں احتیاط
سے کام لینا چاہئے.جیسا کہ قرآن شریف بھی فرماتا ہے:.↓
” إِنْ جَاءَ كُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا
یعنی اگر تمہارے پاس کوئی جھوٹا شخص ایک خبر لاتا ہے تو اُسے یونہی بلاتحقیق نہ
مان لیا کرو بلکہ تحقیق کے بعد اگر درست ثابت ہو تو تب مانا کرو“
الغرض شہادت حصول علم کے ذرائع میں سے ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اور صرف
اس احتمال سے کہ بعض شہادتیں غلط بھی ہو سکتی ہیں اس ذریعہ کو ہر گز نظر انداز نہیں کیا
جاسکتا کیونکہ اگر اس قسم کے احتمالات سے کسی چیز کو باطل قراردیا جا سکتا ہے تو پھر دُنیا کی
سورة الحجرات - آیت 7
150
Page 151
کوئی چیز بھی ایسی نہیں رہتی کہ جو قابلِ تسلیم ہو سکے کیونکہ ہر چیز کے متعلق خواہ وہ کیسی ہی
یقینی ہو اس قسم کے احتمالات کا دروازہ کھلا ہے.خوراک انسان کی بھوک کو دور کرتی ہے
اور اس کے جسم کی ترقی اور طاقت کی بحالی کا موجب ہے لیکن کیا خوراک بعض اوقات
گندی اور خراب نہیں ہوتی جو بجائے جسم کے لئے مفید ہونے کے اُسے الٹا نقصان
پہنچا دیتی ہے؟ مگر کیا کوئی ایسا شخص ہے جو اس احتمال کی وجہ سے یہ نتیجہ نکالے کہ خوراک
جسم انسانی کے لئے ضرر رساں ہے؟ بات یہ ہے کہ ہر چیز خواہ وہ کیسی ہی مفید اور فائدہ
مند ہو غلط ہاتھوں میں جاکر اور غلط استعمال میں آکر نقصان دہ ہو جاتی ہے.پس
ضرورت صرف اس احتیاط کی ہے کہ کسی چیز کا غلط استعمال نہ ہو اور اصولِ شہادت کا غلط
استعمال یہ ہے کہ کسی در ونگو یا ناقض الفہم یا مخبوط الحواس شخص کی شہادت
پر کسی فیصلہ کی
بنیاد رکھدی جاوے.اگر ہم اس غلط استعمال سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں تو پھر
شہادت ایک نہایت مفید اور قابلِ اعتماد ذریعہ حصول
علم کا قرار پاتی ہے جس سے کوئی
عقلمند انکار نہیں کرسکتا.مذکورہ بالا اصول کے ماتحت ہم ہستی باری تعالیٰ کے عقیدہ پر نظر ڈالتے ہیں تو یہ
عقیدہ دنیا کی مضبوط ترین شہادت سے پایہ ثبوت کو پہنچا ہو انظر آتا ہے.دنیا میں جتنے
بھی نبی اور رسول آئے ہیں خواہ وہ کسی ملک یا کسی قوم یا کسی زمانہ میں مبعوث ہوئے
ہوں ہمارے سامنے یہ شہادت پیش کرتے ہیں کہ دُنیا کا ایک خُدا ہے جو اس تمام
کارخانہ عالم کا خالق و مالک و متصرف ہے اور وہ محض کسی خیال یاسنی سنائی بات کی بنا پر
ایسا نہیں کہتے بلکہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے اُس خدا کو اسی طرح دیکھا اور پہچانا ہے
جس طرح ہم دنیا کی دوسری غیر مادی چیزوں کو دیکھتے اور پہچانتے ہیں اور اس خدا کے
ساتھ ہمارے ذاتی تعلقات قائم ہیں اور ہم اس کی ہستی کے متعلق ایسا ہی یقین رکھتے
ہیں جیسا کہ مثلاً ہمیں یہ یقین ہے کہ فلاں شخص ہمارا باپ ہے اور فلاں ہمارا بھائی ہے
151
Page 152
اور فلاں ہمارا دوست ہے اور فلاں ہمارا شہر ہے اور فلاں ہمارا امکان ہے وغیرہ وغیرہ اور
یہ کہ خدا ہم سے کلام کرتا ہے اور ہماری باتوں کو سنتا اور ان کا جواب دیتا ہے اور ضرورت
کے وقت ہماری نصرت فرماتا ہے.الغرض تمام نبی اور رسول نہایت واضح اور
غیر
مشکوک الفاظ میں ہمارے سامنے اس شہادت کو پیش کرتے ہیں کہ اس دُنیا کے اوپر
ایک خالق و مالک خدا ہے.اور جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے ان کی شہادت کسی سنی سنائی
بات پر مبنی نہیں بلکہ اُن کے ذاتی تجربہ اور مشاہدہ پر مبنی ہے اور کسی ایک ملک یا ایک قوم یا
ایک زمانہ تک محدود نہیں بلکہ ہر ملک اور ہر قوم اور ہر زمانہ میں پائی جاتی ہے.حضرت
آدم ہیں تو اس کے شاہد ہیں.حضرت نوح ہیں تو اس کے شاہد ہیں.حضرت یونس و
ایوب ہیں تو اس کے شاہد ہیں.حضرت ابراہیم ولوط ہیں تو اس کے شاہد ہیں.حضرت
اسمعیل و اسحاق ہیں تو اس کے شاہد ہیں.حضرت یعقوب و یوسف ہیں تو اس کے شاہد
ہیں.حضرت موسی و ہارون ہیں تو اس کے شاہد ہیں.حضرت داؤد وسلیمان ہیں تو اس
کے شاہد ہیں.حضرت
زکریا و یحی" ہیں تو اس کے شاہد ہیں.حضرت مسیح ناصری ہیں تو
اس کے شاہد ہیں پھر زرتشت ہیں تو اس کے شاہد ہیں.کنفیوشس ہیں تو اس کے شاہد
ہیں.کرشن اور رامچند رہیں تو اس کے شاہد ہیں.پھر حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم
ہیں تو اس کے شاہد ہیں اور اس زمانہ میں حضرت
مسیح موعود علیہ السلام ہیں تو اس کے شاہد
ہیں اور ان کے علاوہ بھی جتنے بانیان مذاہب دنیا میں گزرے ہیں سب اس معاملہ میں
اپنی ذاتی شہادت ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں کہ یہ دنیا ایک خالق و مالک، قدیر
و متصرف خدا کے ماتحت ہے جس کے قبضہ قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں.اور یہ وہ لوگ
ہیں جن کی راست گفتاری اور دیانت وامانت دوست و دشمن میں مسلم ہے.یعنی دشمن
بھی اس بات کو مانتا ہے کہ خواہ ان کالا یا ہو امذہب ہم قبول کریں یا نہ کریں لیکن اس میں
کلام نہیں کہ یہ سب لوگ اپنی ذات میں راستباز اور صادق القول ہیں اور پھر یہ لوگ
152
Page 153
مجنون یا ناقص الفہم یا مخبوط الحواس بھی نہیں ہیں بلکہ اُن لوگوں میں شمار کئے جاتے ہیں جو
دل و دماغ کی اعلیٰ ترین طاقتیں لے کر دُنیا میں آئے تھے.اندریں حالات ان لوگوں
کی شہادت اہل بصیرت کے نزدیک وہ وزن رکھتی ہے جو کسی اور شہادت کو حاصل نہیں
ہوسکتا.میرے عزیز و ! خوب سوچو اور غور کرو کہ دنیا کے مختلف حصوں میں مختلف قوموں
میں مختلف زمانوں میں مختلف لوگ پیدا ہوتے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی
راست گفتاری اور دیانت و امانت ہر قسم کے شک وشبہ کے احتمال سے بالا ہے اور ان کی
دماغی حالت بھی پوری طرح صحیح اور تمام نقصوں سے پاک سمجھی گئی ہے.بلکہ وہ اپنی
بے مثل راست گفتاری اور اعلیٰ دماغی طاقتوں میں دوسروں کے واسطے ایک نمونہ سمجھے
جاتے ہیں اور یہ لوگ تعداد میں بھی دس ہیں یا سو پچاس نہیں بلکہ ہزاروں ہیں اور مختلف
ملکوں اور مختلف زمانوں میں پھیلے ہوئے ہیں.اور یہ سب لوگ دنیا کے سامنے اپنی ذاتی
شہادت پیش کرتے ہیں کہ یہ دنیا و مافیہا ایک بالا ہستی کے قبضہ و تصرف میں ہے.اور یہ
کہ ہم نے اس بالا ہستی کو اسی طرح دیکھا اور محسوس کیا ہے جس طرح ہم دوسری غیر مادی
چیزوں کو دیکھتے اور محسوس کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہمارے اسی طرح کے تعلقات
قائم ہیں جس طرح ہم اس دنیا کی محسوس و مشہور چیزوں کے ساتھ تعلقات رکھتے ہیں.کیا یہ شہادت اس قابل نہیں کہ اسے قبول کیا جاوے؟ اگر یہ شہادت قابل قبول نہیں تو
دنیا میں کوئی شہادت بھی ایسی نہیں ہو سکتی جو قابل قبول ہو.دو ہی باتیں ہیں جو کسی شہادت کے متعلق شبہ پیدا کر سکتی ہیں.اول یہ کہ شاہد
کی راست گفتاری مشتبہ ہو’ دوسرے یہ کہ شاہد ناقص الفہم ہو.کیونکہ اس سے یہ احتمال
پیدا ہوتا ہے کہ گو وہ دیدہ و دانستہ جھوٹ نہ بولے لیکن بوجہ ناقص الفہم ہونے کے اس
مشاہدہ اور تجربہ میں غلطی واقع ہوسکتی ہے لیکن یہاں یہ دونوں باتیں مفقود ہیں اور نہ
153
Page 154
صرف مفقود ہیں بلکہ یہ شاہد وہ ہیں جو اپنی صادق القولی اور اعلیٰ دماغی طاقتوں میں دُنیا
کی صف اول میں شمار کئے گئے ہیں.اور پھر وہ شہادت بھی کوئی سماعی شہادت پیش نہیں
کرتے بلکہ اپنا ذاتی اور عینی مشاہدہ پیش کرتے ہیں اور یہ لوگ گزرے بھی مختلف
زمانوں اور مختلف قوموں میں ہیں.بلکہ اُن میں سے اکثر وہ ہیں جن کو اپنے زمانہ میں
دوسروں کے وجود تک کی اطلاع نہ تھی اس لئے اُن کے متعلق سازش کا بھی شبہ نہیں
ہوسکتا.اندریں حالات اُن کی یہ شہادت ایسی وزن دار شہادت ہے کہ جو کسی صورت
میں نظر انداز نہیں کی جاسکتی.یوں سمجھو کہ تمہارے پاس ایک مقدمہ آتا ہے اور تم نے اس کا فیصلہ کرنا ہے.ایک طرف ہزاروں انسانوں کی جماعت ہے جن کے ایک ایک فرد کی راست گفتاری
اور صحیح الدماغی دوست و دشمن میں مسلم ہے اور یہ لوگ الگ الگ اپنی عینی شہادت پیش
کرتے ہیں کہ ہم نے فلاں شخص کو فلاں جگہ دیکھا ہے اور دوسری طرف ایک گروہ ہے
جس میں ہر قسم کے بُرے بھلے لوگ شامل ہیں اور وہ یہ بیان دیتے ہیں کہ ہم نے اس
شخص کو نہیں دیکھا.بتاؤ تم کس فریق کے حق میں فیصلہ دو گے؟ اگر تم اپنے اندر فیصلہ کی
طاقت نہیں پاتے تو کسی قانون دان سے جا کر پوچھو وہ تمہیں بتائے گا کہ اگر دیکھنے
والوں کی شہادت شبہ سے بالا ہے تو اُسی کے مطابق فیصلہ ہوگا اور نہ دیکھنے والوں کا بیان
خواہ وہ تعداد میں کتنے ہی زیادہ ہوں فیصلہ پر کوئی اثر نہیں پیدا کر سکے گا کیونکہ یہ تو مکن
ہے کہ ایک چیز موجود ہو اور کسی وجہ سے بعض لوگ اُسے نہ دیکھیں لیکن یہ بات ہرگز ممکن
نہیں کہ ایک چیز موجود نہ ہو اور پھر بھی عاقل اور صحیح الدماغ لوگوں کی ایک جماعت اُسے
دیکھ لے.الغرض انبیاء اور رسل کی شہادت جو وہ ہستی باری تعالیٰ کے متعلق پیش کرتے
ہیں اس بات کا ایک نہایت زبردست ثبوت ہے کہ واقعی ہمارا ایک خدا موجود ہے.اور
154
Page 155
اگر انبیاء اور رسل کے ساتھ دنیا کی مختلف قوموں کے صلحاء اور اولیاء کو بھی شامل کر لیا
جائے تو پھر یہ شہادت ایسی وزن دار ہو جاتی ہے کہ اس کا انکار قریباً قریباً جنون کے حکم
میں آجاتا ہے.ہر اُمت میں لاکھوں صلحاء اور اولیاء گذرے ہیں جو اپنے اپنے حلقہ میں
اپنی بزرگی اور عقل و دانش کی وجہ سے لوگوں کے قلوب پر حکومت کرتے رہے ہیں اور
اُن کی راست گفتاری اور امانت و دیانت لوگوں کے واسطے نمونہ رہی ہے.یہ لوگ بھی
انبیاء کی طرح اس بات کی شہادت دیتے رہے ہیں کہ دنیا کا ایک خُدا ہے جس کے
قبضہ تصرف کے ماتحت یہ سارا کارخانہ عالم چل رہا ہے.اور یہ شہادت بھی کوئی سنی سنائی
شہادت نہیں بلکہ انبیاء کی طرح ان لوگوں کے ذاتی مشاہدہ پر مبنی ہے.پس جب تک یہ
ثابت نہ کیا جائے کہ یہ لاکھوں بلکہ کروڑوں انبیاء اور اولیاء اور صلحاء جو مختلف زمانوں اور
مختلف قوموں میں ظاہر ہوتے رہے ہیں نعوذ باللہ دروغ گو تھے یا مخبوط الحواس اور
ناقص العقل تھے اس وقت تک ان لوگوں کی یہ عظیم الشان شہادت کہ ہم نے خدا کو دیکھا
اور پہچانا ہے اور اس کے ساتھ ہمارا ذاتی تعلق قائم ہے، ایک ایسا گراں پتھر ہے جسے کوئی
دہر یہ اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتا.کیا کوئی دہر یہ یہ جرات کر سکتا ہے کہ مرد میدان بن کر
دنیا کے سامنے آئے اور اس بات کو ثابت کرے کہ حضرت ابراہیم دروغگو تھے یا مجنون
تھے.حضرت موسی دروغگو تھے یا مجنون تھے.حضرت مسیح دروغگو تھے یا مجنون تھے.حضرت کرشن دروغگو تھے یا مجنون تھے.زرتشت دروغگو تھے یا مجنون تھے.آنحضرت
صلحم دروغگو تھے یا مجنون تھے.حضرت مسیح موعود دروغگو تھے یا مجنون تھے.اور اسی طرح
باقی تمام انبیاء بھی دروغگو تھے یا مجنون تھے.اور یہ جو ہر امت میں بے شمار صلحاء اور اولیاء
گذرے ہیں یہ بھی سب
درونگو تھے یا مجنون تھے؟ اور اگر کوئی دہر یہ یہ ثابت نہیں کرسکتا
تو کیا یہ افسوس کا مقام نہیں کہ تم لنڈن کو باوجود نہ دیکھنے کے مانو کیونکہ دیکھنے والے کہتے
ہیں کہ لنڈن ایک شہر ہے اور قطب شمالی اور قطب جنوبی کو با وجود نہ دیکھنے کے مانو کیونکہ
155
Page 156
دیکھنے والے کہتے ہیں کہ وہ موجود ہیں؟ اور دوسرے ممالک کے واقعات کو جو اخباروں
بھیتے ہیں باوجود خود نہ دیکھنے کے مانو؟ کیونکہ رائیٹر یا ہواس یا کوئی اور خبر رساں
سی کہتی ہے کہ وہ وقوع پذیر ہوئے ہیں.اور سائنس کی جدید تحقیقاتوں کو باوجود خود
تجربہ نہ کرنے کے مانو کیونکہ تجربہ کرنے والے کہتے ہیں کہ وہ صحیح ہیں، مگر خدا کو باوجود
اس کے کہ لاکھوں صحیح الدماغ راستباز اس کے موجود ہونے کی ذاتی شہادت پیش کرتے
ہیں تسلیم نہ کرو! تِلْكَ إِذَا قِسْمَةٌ ضِيْرَى
اور اگر کہو کہ یہ باتیں جو دوسرے لوگ پیش کرتے ہیں یہ گو ہم نے خود نہیں
دیکھیں لیکن ان کے دیکھنے اور مشاہدہ کرنے کا رستہ تو ہمارے واسطے کھلا ہے.تو میں کہتا
ہوں کہ اے ہمارے بھولے بسرے دوستو !خد اتمہاری آنکھیں کھولے یہ رستہ تمہارے
لئے خدا کے متعلق بھی گھلا ہے کیونکہ جو لوگ خدا تک پہنچنے کے مدعی ہیں وہ ساتھ ہی یہ
بھی کہتے ہیں کہ اگر تم اس طریق کو اختیار کرو جو ہم بتاتے ہیں اور جو خدا تک پہنچنے کا
طریق ہے تو تم بھی ہماری طرح خدا کومل سکتے اور اس کے ساتھ تعلق پیدا کر سکتے ہو.اور یہ اُن کا خالی دعوئی ہی نہیں ہے بلکہ بے شمار لوگوں نے ان کی پیروی اختیار کر کے
واقعی خدا کا عرفان حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کر لی ہے چاہو تو آزما دیکھو.مگر
افسوس کہ دُنیا کے مقاصد کے متعلق تو لوگ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اُن میں سے ہراک کے
حصول کا ایک معتین طریق ہے جسے اختیار کئے بغیر وہ مقصد حاصل نہیں ہوسکتا اور ہر
مقصد کا حصول کچھ وقت بھی چاہتا ہے لیکن روحانی مقاصد کے متعلق یہ امید رکھتے ہیں
کہ وہ صرف خواہش کرنے سے ہی فوراً حاصل ہو جایا کریں.ایسا ہر گز نہیں ہوسکتا.اور
اگر عقل رکھتے ہو تو سوچو کہ ایسا ہونا بھی نہیں چاہئے.حق یہی ہے چاہو تو قبول کرو کہ ہر
مقصد کے حصول کے واسطے خواہ وہ مادی ہے یا رُوحانی ایک خاص طریق مقرر ہے اور
Havas
سورة النجم - آیت 23
156
Page 157
جب تک انسان اس طریق کو اختیار نہ کرے وہ مقصد کبھی حاصل نہیں ہوسکتا.بلکہ جتنا
بڑا اور جتنا اعلیٰ مقصد ہوتا ہے اُتنا ہی اس کے واسطے زیادہ وقت صرف کرنا پڑتا ہے،
زیادہ توجہ دینی پڑتی ہے، زیادہ محنت اٹھانی پڑتی ہے، زیادہ قربانی کرنی پڑتی ہے، زیادہ
لمبے ضابطہ عمل میں سے گذرنا پڑتا ہے، تب جا کر وہ مقصد حاصل ہوتا ہے مگر تم ہاتھ پر
ہاتھ دھر کر بغیر کچھ کئے کے یہ اُمید رکھتے ہو کہ اگر کوئی خُدا ہے تو وہ ہمیں مل جائے.خدا
نکی قسم تم اس طرح خدا کو کبھی نہیں پاؤ گے.ہاں اگر سچی تڑپ اور دلی آرزو اور پوری توجہ
اور واجبی محنت کے ساتھ اس طریق کو اختیار کرو جو خدا تک پہنچنے کا طریق ہے اور پھر بھی
خدا کو نہ پاؤ تو تب یہ کہنے کا حق رکھو گے کہ ہم نے خدا کو تلاش کیا مگر نہ پایا.مگر یہ ناممکن
ہے کہ تم ٹھیک راستہ پر چل کر خدا کو تلاش کرو اور پھر بھی خدا تمہیں نہ ملے.لاکھوں بلکہ
کروڑوں انسانوں نے جو تمہاری طرح کے انسان تھے اور تمہاری طرح کا دل و دماغ
رکھتے تھے خدا کو تلاش کیا اور آخر اُس کو پالیا اور تاریخ عالم کے صفحات پر ان لوگوں کی
شہادت ہاں ذاتی اور عینی شہادت واضح اور غیر مشکوک شہادت ثبت ہے.اور تم میں سے
کوئی شخص یہ جرات نہیں کر سکتا کہ اُن کی شہادت کے متعلق کسی قسم کے شک وشبہ کا احتمال
پیدا کر سکے.تم اُنکو دھوکہ باز نہیں کہہ سکتے.تم انکو ناقص العقل اور مخبوط الحواس نہیں کہہ
سکتے.تم ان کے متعلق یہ شبہ نہیں کر سکتے کہ انہوں نے باہم ملکر ایک بات بنالی ہے.پس
کوئی وجہ نہیں کہ تم اُن کی شہادت کو محض اپنے دماغ کے فرضی تخیلات کی بناء پر رڈ کر دو.اور اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ہم ان لوگوں کو دھو کے باز یا ناقص العقل نہیں کہتے بلکہ
دھو کہ خوردہ کہتے ہیں اور دھو کہ ہر انسان کو کم و بیش لگ سکتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ
بیشک اس بات کا امکان ہے کہ ایک فہمیدہ آدمی کو بھی کبھی دھو کہ لگ جائے لیکن کسی بات
کے امکان ہونے کے یہ معنے نہیں ہیں کہ وہ بات عملاً وقوع میں بھی آگئی ہے یعنی صرف
اتنی بات کہہ دینے سے کہ دھو کہ لگ جانے کا امکان ہے یہ ثابت نہیں ہو جاتا کہ واقعی
157
Page 158
دھوکا لگا بھی ہے.پس جب تک یہ ثابت نہ کیا جائے کہ یہ سب لوگ اس معاملہ میں
واقعی دھو کہ خوردہ تھے اُس وقت تک محض دھوکا لگنے کا امکان بیان کر دینے سے معترض کا
مطلب حل نہیں ہوسکتا.وہ کون سی بات ہے جس میں دھو کے کا امکان نہیں ہے تو کیا اس
وجہ سے دنیا کی ساری باتوں کو مشکوک قرار دیا جا سکتا ہے؟ اس طرح تو تو ہم پرستی کا ایسا
دروازہ کھل جاتا ہے کہ کوئی بات بھی یقینی نہیں رہتی.نپس جو شخص اس بات کا مدعی بنتا
ہے کہ یہ شہادت دینے والے سب کے سب بلا استثناء اس معاملہ میں دھو کہ خوردہ ہیں
اس کا یہ فرض ہے کہ اپنے اس دعویٰ کو دلائل کے ساتھ ثابت کر کے دکھائے والا صرف
مُنہ کی پھونکوں سے لاکھوں راستباز صحیح الدماغ بزرگوں کی شہادت کو اڑا دینے کی کوشش
کرنا ایک طفلانہ فعل ہے جس کی طرف کوئی عقلمند توجہ نہیں کرسکتا.شہادت دینے والوں
نے شہادت دی ہے اور واضح اور غیر مشکوک الفاظ میں دی ہے اور کوئی سنی سنائی شہادت
نہیں دی بلکہ اپنا ذاتی اور عینی مشاہدہ پیش کیا ہے اور یہ شہادت دینے والے بزرگ سب
کے سب راستباز اور صحیح الدماغ انسان ہیں اور پھر تعداد میں بھی وہ کم از کم لاکھوں ہیں
اور ہر قوم اور ہر ملک اور ہر زمانہ میں پھیلے ہوئے ہیں.ایسے حالات میں صرف اتنا کہہ
دینے سے کہ دھوکہ لگنے کا امکان ہے یہ سمجھ لینا کہ بس یہ شہادت مشکوک ہو گئی ایک
مجنونانہ فعل ہے جس پر کوئی دل و دماغ رکھنے والا انسان
تسلی نہیں پاسکتا.دوسرا جواب اس اعتراض کا جومیں دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دھو کہ لگنے کے
بھی موقعے اور حالات ہوتے ہیں اور ہر جگہ یہ نہیں کہا جاسکتا کہ دھو کہ لگا ہوگا.ایک
عاقل اور صحیح الدماغ شخص کے لئے دھوکا لگنے کا امکان صرف ان صورتوں میں ہو سکتا ہے
کہ جہاں رائے اور خیال کا دخل ہوا اور دلائل کی بنا پر فیصلہ کرنا ہو.مثلاً ایک علمی مسئلہ میں
یہ امکان ہے کہ دو شخص دو مختلف خیال رکھتے ہوں اور دونوں صحیح الدماغ بھی ہوں کیونکہ
جہاں رائے اور استدلال کا دخل ہے وہاں اس بات کا امکان ہے کہ کسی غلط فہمی کی وجہ
158
Page 159
سے غلطی لگ جائے.لیکن جہاں مشاہدہ کا سوال ہے وہاں ایک صحیح الدماغ اور
صحیح الحواس شخص کے واسطے دھو کے کا امکان نہیں رہتا خصوصاً جبکہ یہ مشاہدہ ایسی چیز سے
تعلق رکھتا ہو جس کے متعلق وہ شخص یہ دعویٰ رکھتا ہے کہ وہ اس کی خاص دلچپسی کی چیز
ہے اور دن رات اس کے سامنے رہتی ہے اگر ایسی حالت میں بھی ایک صحیح الدماغ مشخص
کے واسطے دھوکا لگنے کا امکان تسلیم کیا جاوے تو پھر خطر ناک تو ہم پرستی کا دروازہ کھل جاتا
ہے اور دنیا سے امن اُٹھ جاتا ہے اور کوئی مشاہدہ بھی یقینی نہیں رہتا.کیا کسی صحیح الدماغ
شخص کو یہ دھوکا لگ سکتا ہے کہ وہ کسی غیر اور اجنبی شخص کے متعلق یہ سمجھنے لگ جائے کہ یہ
شخص میرا فلاں دوست ہے جس کے ساتھ اتنے سالوں سے میرے دوستانہ تعلقات
ہیں یا ایک ناواقف شخص کو اپنا پاپ یا بھائی سمجھنے لگ جائے ؟ ظاہر ہے کہ ایسا دھوکا
سوائے ایک مجنون یا مخبوط الحواس شخص کے اور کسی کو نہیں لگ سکتا.اب اس اصل کے ماتحت ہم انبیاء وصلحاء کی شہادت پر نظر ڈالتے ہیں تو ان کی
شہادت بھی دھوکا لگنے کے امکان سے بالا تسلیم کرنی پڑتی ہے کیونکہ وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم
نے عقلی دلائل سے خدا کی ہستی پر اطلاع پالی ہے اور بس.بلکہ وہ یہ دعوی کرتے ہیں کہ
ہم نے واقعی خدا کو پالیا ہے اور اس کے ساتھ ہمارا ذاتی تعلق قائم ہو گیا ہے اور وہ ہم
سے کلام کرتا اور ہماری باتوں
کو سنتا اور اُن کا جواب دیتا ہے اور ضرورت کے وقت اپنی
زبر دست طاقتوں کے ساتھ ہماری نصرت فرماتا ہے.اور پھر وہ اپنے اس مشاہدہ کو اپنی
عمر کے کسی خاص حصہ کی طرف منسوب نہیں کرتے بلکہ اس بات کے مدعی ہیں کہ جب
سے ہم نے خدا کو پایا ہے اس کے بعد سے ہماری ساری عمر اسی مشاہدہ میں گذری ہے.گویا ان کا یہ مشاہدہ ایک غیر منقطع عرصہ کی صورت میں سالہا سال پر پھیلا ہوا ہے اور
مرتے دم تک ان سے جُد انہیں ہوا اور اُن کے مشاہدہ کے عملی نتائج بھی دنیا کے سامنے
ہیں.ایسی صورت میں کوئی عقلمند آدمی ان کے متعلق یہ خیال نہیں کر سکتا کہ انہیں دھوکا لگا
159
Page 160
ہوگا.کیونکہ اگر ان حالات میں بھی دھو کے کا احتمال تسلیم کیا جائے تو پھر ہمارا کوئی مشاہدہ
بھی اس احتمال سے باہر
نہیں سمجھا جاسکتا.اور دُنیا کے سارے علوم محض سفسطہ اور وہم کی
صورت اختیار کر لیتے ہیں.بے شک ایسی صورت میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ شہادت دینے
والوں کے دماغ میں نقص ہے لیکن اُن کو صحیح الدماغ تسلیم کر کے دھوکا خوردہ قرار نہیں دیا
جاسکتا.تیسرا جواب اس اعتراض کا یہ ہے کہ یہ شہادت کسی ایک فرد کی نہیں ہے، کسی
ایک قوم کے لوگوں کی نہیں ہے، کسی ایک ملک کے باشندوں
کی نہیں ہے، کسی ایک زمانہ
کے لوگوں کی نہیں ہے.بلکہ لاکھوں انسانی کی ہے جو دنیا کے ہر ملک ہر قوم ہر ملت ہر
زمانہ میں پھیلے ہوئے ہیں.پس تم رکس کس کو دھوکا خوردہ قرار دو گے؟ ایک کو دھوکا لگ
سکتا ہے، دوکو دھوکا لگ سکتا ہے، کسی ایک زمانہ میں دھوکا لگ سکتا ہے، کسی ایک قوم میں
دھوکا لگ سکتا ہے لیکن یہ عجیب دھوکا ہے کہ لاکھوں صحیح الدماغ شخص جو مختلف قوموں اور
مختلف زمانوں اور مختلف ملکوں میں عموماً ایک دوسرے سے بے خبری کی حالت میں
گذرے ہیں سارے کے سارے اس دھو کے کا شکار ہو گئے.پس اس شہادت میں اتنی
بڑی جماعت کا پیش ہونا اور ہر قوم، ہر ملت ، ہر زمانہ اور ہر ملک کی طرف سے پیش ہونا
اور سب کا ایک دوسرے سے آزاد ہو کر مستقل طور پر الگ الگ اس شہادت کا دینا ایک
ایسی دلیل ہے جس میں کوئی عقلمند دھوکا لگنے کا احتمال تسلیم نہیں کر سکتا.خلاصہ کلام یہ کہ انبیاء اور اولیاء اور صلحاء یہ کہتے ہیں اور ڈنکے کی چوٹ کہتے ہیں
کہ ہم نے خدا کو دیکھا اور پہچانا ہے اور دنیا تسلیم کرتی ہے کہ وہ دروغگو نہیں ، دوکاندار
نہیں، مجنون نہیں، مخبوط الحواس نہیں.اور یہ بھی مسلم ہے کہ وہ ایک دو نہیں، دس ہیں
نہیں سینکڑوں نہیں ، ہزاروں نہیں، لاکھوں بلکہ شاید کروڑوں ہیں.اور ہر ملک، ہر قوم
ہر ملت ، ہر زمانہ میں پھیلے ہوئے ہیں اور ان میں سے ہر شخص دوسرے سے آزاد ہو کر
160
Page 161
مستقل طور پر اپنی شہادت پیش کرتا ہے.اور یہ شہادت بھی کسی سنی سنائی بات پر مبنی نہیں
بلکہ ذاتی اور گویا عینی مشاہدہ پر مبنی ہے اور یہ مشاہدہ بھی ایسا ہے کہ جو ان لوگوں کی ساری
عمر پر پھیلا ہوا ہے.پس ہم مجبور ہیں کہ جس طرح ہم دنیا کے دوسرے امور میں شہادت
پر اپنے علم اور فیصلہ کی بنارکھتے ہیں اسی طرح ان کی شہادت کو بھی قبول کر کے اس بات
کے قائل ہوں کہ یہ دنیا ایک واحد، خالق و مالک علیم و حکیم، قدیر و متصرف ہستی کے
ماتحت ہے جس کے قبضہ قدرت سے دُنیا کی کوئی چیز با ہر نہیں.قرآن شریف نے بھی اس شہادت کے اصول کو پیش کیا ہے بلکہ اسی اصل کے
ماتحت انبیاء کا ایک نام قرآن شریف میں شاہد رکھا گیا ہے.چنانچہ فرماتا ہے:.إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُوْلاً " شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ
رَسُوْلاً
یعنی ” اے لوگو! ہم نے تمہاری طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا
ہے
تا کہ وہ تمہارے لئے شاہد یعنی گواہ کا کام دیں جیسا کہ ہم نے فرعون کی طرف موسیٰ
رسول کو شاہد بنا کر بھیجا تھا.“
الغرض شہادت رسل وصالحین کی دلیل خدا تعالیٰ کی ہستی کی ایسی زبردست دلیل
ہے کہ کوئی سمجھ دار شخص اس کا انکار نہیں کر سکتا.آب میں بفضلہ تعالیٰ ان عقلی دلائل کی بحث ختم کر چکا ہوں جو میں اس مضمون
میں مستی باری تعالیٰ کے متعلق بیان کرنا چاہتا تھا اور ان دلائل کے متعلق جو جو شبہات
عقلی طور پر وارد ہو سکتے ہیں انکا جواب بھی مختصر طور پر ساتھ ساتھ درج کر دیا گیا ہے.مگر
جیسا کہ میں نے ابتدائے مضمون میں بیان کیا تھا میں نے اس مضمون میں پیچیدہ اور
بار یک بحثوں سے حتی الوسع اجتناب کیا ہے اور صرف موٹی موٹی باتیں عام فہم طریق پر
↓
ل سورة المزمل - آیت 16
161
Page 162
بیان کر دی ہیں اور میں اُمید کرتا ہوں کہ ایک سلیم الفطرت اور فہمیدہ انسان جو خواہ نخواہ
شبہات پیدا کرنے کا عادی نہیں ہے میرے اس مختصر بیان سے اس حد تک ضرور تسلی
پاسکے گا جس حد تک کہ عقلی دلائل کے امکان میں ہے.باقی جیسا کہ میں اس مضمون
میں دوسری جگہ ذکر کر چکا ہوں حقیقی اطمینان اور عین الیقین تو ذاتی تجربہ اور مشاہدہ سے
ہی حاصل ہوسکتا ہے اور مشاہدہ کے لئے انبیاء اور اولیاء کی زندگیوں کا مطالعہ کرنا اور ان
کے رستہ پر گامزن ہونا ضروری ہے جس کی تھوڑی سی جھلک انشاء اللہ آگے چل کر اپنے
موقعہ پر بیان کی جائے گی.ایمان باللہ کے عظیم الشان فوائد
اس کے بعد میں ہستی باری تعالیٰ کے متعلق چند ایسے دلائل بیان کرنا چاہتا ہوں
جواس اصول پر مبنی ہیں کہ خدا پر ایمان لانا اپنے اندر بعض ایسے اہم فوائد رکھتا ہے جو بغیر
اس پر ایمان لانے کے کسی اور طریق سے پوری طرح حاصل نہیں ہو سکتے.ظاہر ہے کہ
دنیا میں جب کوئی چیز اختیار کی جاتی ہے تو اس اصول پر کی جاتی ہے کہ وہ کس حد تک مفید
اور نفع بخش ہے.بنی نوع انسان پر اس چیز کا اختیار کرنا کیا فائدہ مند اثر پیدا کرتا ہے؟
پس اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ خدا پر ایمان لا نانسلِ انسانی کے لئے بہت مبارک اور
نفع بخش ہے تو ہر عقلمند اس بات سے اتفاق کرے گا کہ اس صورت میں اور نہیں تو صرف
اس فائدہ کی خاطر ہی خدا کے عقیدہ کو ترک نہیں کرنا چاہئے.بیشک ان دلائل سے یہ
استدلال نہیں ہوسکتا کہ اس دنیا کے اوپر کوئی خدا ہے یا ہونا چاہئے.لیکن ان سے یہ
ضرور پتہ چلتا ہے کہ خدا کا عقیدہ نسلِ انسانی کی ترقی اور بہبودی کے لئے نہایت مفید
ہے اور چونکہ مفید چیز اختیار کی جانی چاہیئے اس لئے یہ دلائل بھی ہستی باری تعالیٰ کی تائید
162
Page 163
میں بالواسطہ پیش کئے جاسکتے ہیں.گویا جس طرح میں نے عقلی دلائل کے شروع میں
ایک احتیاطی دلیل بیان کی تھی جو اس اصل پر مبنی تھی کہ چونکہ خدا پر ایمان لانے میں کوئی
نقصان نہیں اور انکار کرنا نقصان کے احتمالات رکھتا ہے اس لئے ایمان لانا
اقرب بالامن ہے.اسی طرح عقلی دلائل کی بحث کے اختتام پر میں یہ دوسری قسم کے
احتیاطی دلائل بیان کرنا چاہتا ہوں جو اس اصول پر مبنی ہیں کہ چونکہ خدا کا عقیدہ
نسل انسانی کے لئے مفید اور نفع بخش ہے اس لئے ایمان لانا بہر حال بہتر اور قابل ترجیح
ہے لیکن اس جگہ یہ بات یادرکھنی چاہئے کہ یہاں ان عظیم الشان فوائد سے بحث نہیں جو
مذہبی یا روحانی طور پر ایمان باللہ اور تعلق باللہ سے انسان کو حاصل ہوتے ہیں.مثلاً خدا
کے ساتھ ذاتی تعلق کا قیام.اُس کی تائید و نصرت کا حصول.علم و عرفان کی ترقی.اُخروی نجات وغیرہ وغیرہ بلکہ یہاں صرف اُن اُصولی فوائد کا ذکر ہے جو خدا تعالیٰ پر
معقولی طور پر ایمان لانے کے نتیجہ میں بنی نوع انسان کو عام طور پر حاصل ہوتے ہیں یا
ہو سکتے ہیں اور اس لئے اس جگہ صرف ان مؤخر الذکر فوائد کا ہی ذکر کیا جائے گا.ایمان باللہ وحدت اور اخوت کا جذبہ پیدا کرتا ہے
سب سے پہلے جو فائدہ ایمان باللہ کا میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ خدا کا
خیال لوگوں کے دلوں میں وحدت و اخوت کے جذبات پیدا کرنے کا سب سے بڑا
ذریعہ ہے اور یہ جذبات نسلِ انسانی کی ترقی اور بہبودی کے لئے نہایت درجہ ضروری
اور مفید ہیں.دنیا کے امن اور اقوام عالم کی خاطر خواہ ترقی و بہبودی کے لئے یہ بات
از بس ضروری بلکہ لابدی ہے کہ مختلف اقوام باہم محبت اور اخوت اور تعاون کے ساتھ
رہیں اور ایک دوسرے کے خلاف بے جا تعصب کو اپنے دل میں جگہ نہ پکڑنے دیں بلکہ
حتی الوسع دوسروں کے متعلق ہمدردی اور قربانی اور ایثار کا طریق اختیار کریں اور اسی
163
Page 164
طرح افراد کے لئے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ ایک دوسرے کے متعلق محبت اور اخوت اور
ہمدردی اور تعاون کی روح پیدا کریں کیونکہ بغیر اس رُوح کے جو افراد اور اقوام ہر دو کے
واسطے ایک سی ضروری ہے، دنیا میں امن کا قیام اور نسل انسانی کی خاطر خواہ ترقی
و بہبودی محال ہے.پس ہر اک بہی خواہ نسل آدم کا یہ فرض ہے کہ وہ تمام ایسے ذرائع
اختیار کرنے کے درپے رہے جن سے کہ باہم وحدت و اخوت کی روح پیدا ہوتی اور
ترقی کرتی رہے اور بغض اور حسد اور بے جا رقابت اور تعصب کے خیالات دلوں میں
جاگزیں نہ ہونے پائیں.اور جیسا کہ میں نے اوپر بیان کیا ہے ان ذرائع میں خدا کا
یدہ سب سے بڑا اور سب سے زیادہ قطعی الاثر ذریعہ ہے.واقعی یہ عقیدہ کہ ہم سب لوگ باوجود اپنے کثیر التعداد اور گونا گوں اختلاف کے
ایک واحد قادر و متصرف مدرک بالا رادہ خدا کی مخلوق ومملوک ہیں اور ہم سب کا
ملجاء و ماوی وہی یکتا ہستی ہے جس کے قبضہ تصرف سے دُنیا کی کوئی چیز باہر نہیں.جس
مضبوطی اور جس پختگی اور جس وضاحت کے ساتھ ہمارے دلوں میں باہم محبت و وحدت
واخوت کے جذبات پیدا کر دیتا ہے وہ اپنی نظیر نہیں رکھتا.بیشک ایک ملک کا باشندہ ہونا
یا ایک قوم سے تعلق رکھنا یا ایک نظام حکومت کے ماتحت ہونا وغیر ذالک یہ سب ایسی
باتیں ہیں جو کم و بیش وحدت و اخوت کا موجب ہوتی ہیں لیکن سب سے بڑھ کر یہ ایمان
ہے کہ ہم ایک واحد خالق کی پیدا کردہ ہستیاں اور ایک واحد منبع فیوض سے جاری شدہ
نہریں ہیں.اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ ہمارا یہ مالک و آقا ایک فوت شدہ باپ کی طرح
نہیں جس کے بعد نالائق بیٹے بعض اوقات آپس میں لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں
بلکہ وہ اب بھی ہمارے سروں پر زندہ سلامت موجود ہے اور ہمیشہ رہے گا.یہ ایمان تمام
بنی نوع آدم کو فوراً بھائی بھائی بنا کر ایک صف میں کھڑا کر دیتا ہے اور اس یقین کے پیدا
ہوتے ہی دل کی تمام کدورتیں اور کینے اور باہم بغض وعداوت کے خیالات کا فور ہونے
164
Page 165
اور اُن کی جگہ محبت و اخوت اور ایک دوسرے کے لئے ہمدردی اور قربانی کے جذبات
پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں.خدا پر ایمان لانا بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ اپنے آپ کو
ایک ماں باپ کی اولاد سمجھنا.بلکہ حق یہ ہے کہ خدا کو مان کر پھر بندہ کا تعلق خدا کے ساتھ
ایسا گہرا اور ایسا وسیع تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ جس کی مثال دنیاوی رشتوں میں پائی جانی ممکن
الغرض خدا پر ایمان لانا باہم محبت و اخوت کے جذبات پیدا کرنے کے لئے
ایک ایسا زبردست ذریعہ ہے جس کے مقابلہ میں باقی تمام ذرائع پیچ ہیں.بیشک جیسا
کہ میں نے اوپر بیان کیا ہے ملک اور قوم وغیرہ کے خیالات بھی یہ جذبہ پیدا کرتے
ہیں.لیکن اول تو اُن کا اثر ایسا قوی اور گہرا نہیں ہوتا اور دوسرے یہ کہ وہ صرف ایک
محدود حلقہ میں یہ اثر پیدا کر سکتے ہیں اور تمام نسل انسانی کے اندر مشترکہ طور پر ایسے
جذبات پیدا کرنا ان کے لئے ناممکن ہے.بلکہ بسا اوقات ان کا اثر فرقہ بندی اور قوم
پرستی اور بے جا تعصب اور حسد کی صورت میں ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے جو بجائے
مفید ہونے کے اُلٹا نقصان دہ ہوتا ہے.پس صرف خدا کا عقیدہ ہی ایسا ذریعہ ہے جو
نسلِ انسانی کے اندر عالمگیر صورت میں وحدت و اخوت کے جذبات پیدا کرنے کا
موجب ہو سکتا ہے.اور اگر ہم خدا کا خیال لوگوں کے دلوں سے الگ کر لیں تو یہ وحدت
و اخوت کے خیالات فوراً غائب ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور لوگوں کے درمیان
صرف ضابطہ اور معاملہ کے خشک تعلقات باقی رہ جاتے ہیں جو کبھی بھی قلوب کے اندر
کوئی جذباتی رشتہ پیدا نہیں کر سکتے.خوب غور کرو کہ اگر خدا کوئی نہیں اور ہر انسان خود
بخود اپنے آپ سے ہے اور ایک مستقل اور آزاد ہستی رکھتا ہے تو پھر نہ کوئی اخوت رہ سکتی
ہے اور نہ کوئی وحدت بلکہ خود غرضی اور بے جا رقابت اور حسد کا دور دورہ شروع ہو جاتا
ہے جو دنیا میں امن شکنی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے.وہ بات جو یقینی اور قطعی طور پر تمام
165
Page 166
نسلِ انسانی کے اندرا خوت کا جذبہ پیدا کرسکتی ہے وہ صرف خدا کا خیال ہے اور اس کے
سوا کچھ نہیں اور یہ قطعاً ناممکن ہے کہ اس عقیدہ کو الگ کر کے پھر بھی دنیا میں یہ جذبہ
عالمگیر صورت میں ایک زندہ حقیقت کے طور پر قائم رہ سکے.میں یہ نہیں کہتا کہ ہر شخص جو خدا پر ایمان لانے کا مدعی ہے باہم اخوت و وحدت
کے جذبات اپنے دل میں رکھتا ہے کیونکہ دنیا میں سینکڑوں ہزاروں لاکھوں چیزیں
انسان کی حالت پر اثر ڈالتی رہتی ہیں.اس لئے ممکن ہے کہ بعض دوسرے بواعث کی
وجہ سے ایک خدا پر ایمان لانے والے شخص کا دل بھی ان پاکیزہ جذبات سے خالی ہو
اور یہ بھی ممکن ہے کہ کسی آدمی کے دل میں خدا کا خیال ایک ایسا کمزور خیال ہو جو اس
کے دل ودماغ پر اتنا اثر پیدا نہ کر سکے کہ جو اخوت و وحدت کے جذبات پیدا کرنے کے
لئے ضروری ہے لیکن اس میں شک نہیں کہ اُصولی طور پر خدا کا عقیدہ ان جذبات کے
پیدا کرنے والے موجبات میں سب سے اہم اور بڑا ہے.اور اگر کوئی دوسرے موانع نہ
پیش آجا ئیں تو یقیناً ایک مومن باللہ ایک کا فر باللہ کی نسبت نسلِ انسانی کا زیادہ ہمدرد،
زیادہ خیر خواہ ، زیادہ محبت کرنے والا ہوتا ہے.اور ہر وہ شخص جو دل سے خُدا پر ایمان لاتا
ہے اس بات کی شہادت دے گا کہ خدا کا خیال اس کے دل میں بڑے زور کے ساتھ
اخوت اور وحدت کے جذبات پیدا کرتا رہتا ہے اور نہ صرف پیدا کرتا ہے بلکہ ان
جذبات کا اثر اس کے اعمال میں بھی رونما ہوتا ہے اور اگر وہ اپنے نفس کے مطالعہ کا
عادی ہو تو اس کا دل پورے یقین کے ساتھ اس بات کو محسوس کرتا ہے کہ اگر نعوذ باللہ خدا
کا خیال الگ کر لیا جائے تو پھر کبھی بھی اس کی یہ حالت نہیں رہ سکتی.اور انسان تو انسان
ہے ادنیٰ قسم کے حیوانات بلکہ نباتات اور جمادات کے ساتھ بھی یہ عقیدہ ایک قسم کی
محبت اور موانست اور اپنا ہٹ کے جذبات پیدا کرنے کا موجب ہوتا ہے.انگریزی میں ایک مثل ہے لَوْ می لَوْ مَائی ڈاگ“ Love me love)
66
166
Page 167
(my dog یعنی اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو میرے گتے سے بھی محبت کرنی ہوگی.یعنی جن چیزوں کا میرے ساتھ تعلق ہے ان
کو بھی اپنی محبت میں شریک کرنا ہوگا.یہ نشل
فطرت انسانی کے صحیح مطالعہ پر مبنی ہے.واقعی اگر ہمیں خدا پر ایمان اور خدا کے ساتھ
تعلق ہے تو پھر یہ قطعاً ناممکن ہے کہ ہمارا دل مخلوقات اور خصوصاً انسان کی محبت سے خالی
رہ سکے.میں اس بات کو قبول کر سکتا ہوں کہ ایک شخص جو خدا پر ایمان لانے کا مدعی ہے
وہ اپنے دعوئی میں جھوٹا یا دھوکا خوردہ ہے.لیکن یہ بات میں ایک لمحہ کے لئے بھی قبول
نہیں کر سکتا ( کیونکہ یہ فطرت انسانی کے خلاف ہے ) کہ جو شخص واقعی خدا پر ایمان لاتا
ہے اس کا دل مخلوقات کی محبت و ہمدردی کے خیالات سے خالی رہ سکتا ہے اور تاریخ عالم
پر نظر ڈالنے سے بھی یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو سب سے زیادہ پختگی اور
یقین کے ساتھ ایمان باللہ پر قائم ہوئے ہیں وہی وہ لوگ ہیں جو ہمدردی خلق اور محبت
بنی نوع انسان کے جذبات میں سب سے اعلیٰ مرتبہ پر تسلیم کئے جاتے ہیں اور
جوں جوں لوگ اس ایمان میں کمزور ہوتے جاتے ہیں یہ محبت اور اخوت کے جذبات
بھی اُن کے اندر کمزور ہونے شروع ہو جاتے ہیں.الغرض اس میں ذرہ بھر بھی شک
نہیں کہ خدا کا عقیدہ نسل انسانی میں وحدت و اخوت کے جذبات پیدا کرنے کا سب
سے مضبوط اور یقینی اور سریع الاثر ذریعہ ہے.اور چونکہ وحدت و اخوت کے خیالات دنیا
میں قیامِ امن اور اقوامِ عالم کی خاطر خواہ ترقی و بہبودی کے لئے نہایت ضروری ہیں اس
لئے اس جہت سے بھی ہر عظمند انسان کا یہ فرض ہے کہ وہ اس مفید اور بابرکت عقیدہ کو
ہاتھ سے نہ چھوڑے.وھوالمراد.اس جگہ کسی شخص کے دل میں یہ شبہ پیدا ہوسکتا ہے کہ خُدا کے منکرین بھی
بسا اوقات دوسروں کے ساتھ محبت و ہمدردی کا سلوک کرتے اور رفاہِ عام کے کاموں
میں دلچسپی لیتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان جذبات کے پیدا کرنے کے لئے خدا
167
Page 168
پر ایمان لانا ضروری نہیں.اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے یہ دعویٰ ہر گز نہیں کیا کہ یہ
جذبات سوائے ایمان باللہ کے اور کسی ذریعہ سے پیدا ہی نہیں ہو سکتے بلکہ ہم تو خود اس
بات کے قائل ہیں کہ بہت سی چیزیں کم و بیش اس کا موجب ہوتی ہیں.لیکن ہم یہ ضرور
کہتے ہیں کہ تمام بنی نوع آدم میں مجموعی طور پر اکیل واتم صورت میں یہ جذبات صرف
ایمان باللہ کے نتیجہ میں ہی پیدا ہو سکتے ہیں اور باقی ذرائع اپنی کیفیت اور کمیت میں اس
کا مقابلہ نہیں کر سکتے.پس ہمارا دعویٰ صرف اس صورت میں غلط ثابت ہو سکتا ہے جب
کہ یہ بات ثابت کی جائے کہ یا تو از روئے عقل خدا کا عقیدہ اخوت ووحدت کے
خیالات کا موجب ہو ہی نہیں سکتا اور یا یہ کہ تجربہ اور مشاہدہ کی رُو سے یہ دکھایا جائے کہ
خدا پر ایمان لانے والوں کی نسبت خدا کا انکار کرنے والے لوگ نسلِ انسانی کے زیادہ
ہمدرد، زیادہ خیر خواہ اور زیادہ محبت کرنے والے ہوتے ہیں.اور جب تک ان دو باتوں
میں سے کوئی ایک بات ثابت نہ ہو جائے اُس وقت تک کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ
محض اس بنا پر کہ ایک دہر یہ بھی ایک حد تک یہ جذبات رکھتا ہے، یہ غیر طبعی استدلال
کرے کہ خدا کا عقیدہ ان جذبات کے پیدا کرنے کا موجب نہیں یا یہ کہ دہریت ان
خیالات کے پیدا کرنے کی موجب ہے.میں نہیں سمجھ سکتا کہ کوئی ہوش و حواس رکھنے والا انسان ایک لمحہ کے لئے بھی اس
بات کو قبول کر سکتا ہے کہ خود اپنی ذات میں دہریت ان خیالات کا موجب ہوسکتی ہے یا
یہ کہ خُدا کا عقیدہ ایسے جذبات پیدا نہیں کر سکتا.یہ دونوں باتیں اس قدر بین طور پر
غیر طبعی اور خلاف فطرت ہیں کہ کوئی عقلمند آدمی انہیں قبول نہیں کر سکتا.خدا کا وجود (اگر
اسے صحیح صورت میں تسلیم کیا جائے ) وہ مرکزی نقطہ ہے جہاں پہنچ کر تمام مخلوقات بالآخر
جمع ہو جاتی ہے اور وحدت اور جمعیت کا خیال اس نقطہ کے ساتھ لازم وملزوم کے طور پر
لگا ہو ا ہے اور اسے نظر انداز کر دینے کے یہ معنے ہیں کہ اس کا ئنات کو بغیر کسی مرکز یا منبع
168
Page 169
کے تسلیم کیا جائے.اور اس خیال کے آتے ہی وحدت ویگانگت کے خیالات کا فور
ہونے شروع ہو جاتے ہیں.کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ ایک باپ کی اولاد ہونا وحدت
واخوت کا موجب نہیں ہو سکتا بلکہ مختلف باپوں کی اولا دہونا اس کا موجب ہوتا ہے؟ ہرگز
نہیں ہر گز نہیں.پس اگر کبھی مختلف باپوں کے بیٹے آپس میں صلح اور محبت کا طریق رکھتے
ہیں تو ہم اس سے یہ غیر طبعی نتیجہ نہیں نکال سکتے کہ ایک باپ کی اولا د ہونا محبت واخوت کا
موجب نہیں ہوتا بلکہ اس صورت میں ہم یہ سمجھیں گے کہ اس جگہ کوئی اور موجبات اثر
ڈال رہے ہیں جنہوں نے باوجود مختلف باپوں کے بیٹے ہونے کے اُن کو ایک نقطہ پر جمع
کر رکھا ہے نہ یہ کہ مختلف باپوں کی اولا د ہونے نے یہ اثر پیدا کیا ہے.اسی طرح ہر عقلمند
تسلیم کرے گا کہ اگر یہی مختلف باپوں کے بیٹے جنہیں بعض وجوہات نے باوجود اس
اختلاف کے وحدت و یگانگت کی لڑی میں پرورکھا ہے ایک ماں باپ کی اولا د ہوتے تو
پھر اُن کی باہمی محبت و اخوت بہت زیادہ اکمل و اتم صورت میں ظاہر ہوتی.پس اگر خدا
کے منکرین بھی بعض حالات میں نسلِ انسانی کے ساتھ محبت و ہمدردی کا طریق اختیار
کرتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب ہمیں خدا کے عقیدہ کی ضرورت نہیں.کیونکہ یہ
جذبات اپنی کمیت اور کیفیت کے لحاظ سے اکمل اور اتم صورت میں تبھی ظاہر ہو سکتے ہیں
کہ جب علاوہ اور موجبات وحدت کے لوگ خدا کے عقیدہ پر بھی قائم ہوں اور اپنے
آپ کو ایک واحد منبع خلق سے پیدا شدہ ہستیاں اور اور ایک واحد چشمہ حیات سے
جاری شدہ نہریں تسلیم کریں.میرے عزیز و! میں تمہیں یہ کس طرح یقین دلاؤں کہ خدا پر ایمان لانا (بشرطیکہ
وہ حقیقی اور زندہ ایمان ہو ) انسان کے دل میں بنی نوع آدم کی محبت اور خیر خواہی اور اُن
کے ساتھ جذبہ اخوت کا ایک ایسا وسیع سمندر موجزن کر دیتا ہے کہ جس کی کسی دوسری
جگہ نظیر ملنی ناممکن ہے.اور ان جذبات کے پیدا ہونے کے لئے باقی جتنے بھی موجبات
169
Page 170
ہیں وہ اس کے مقابل میں اپنی کمیت اور کیفیت کے لحاظ سے کچھ بھی حقیقت نہیں
رکھتے.اور یہ سوال کہ ایک دہر یہ ایسے جذبات کیوں رکھتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ
عموماً اس کی دو وجوہات ہیں.اول یہ کہ دہر یہ اپنے اردگرد کے مذاہب کی تعلیم سے
محسوس طور پر یا غیر محسوس طور پر متاثر ہو کر اس نتیجہ پر قائم ہوتا ہے کہ نسل انسانی کی
ہمدردی اور محبت ایک مستحسن فعل ہے جسے اگر وہ اختیار نہ کرے تو وہ لوگوں کی نظر سے
گر جائے گا اور اس صورت میں علاوہ اس کی ذاتی بدنامی کے لوگوں کو اس کے عقائد پر
بھی یہ حرف گیری کا موقعہ ملے گا کہ چونکہ یہ شخص دہر یہ ہے اس لئے اس کے دل میں
بنی نوع انسان کے متعلق محبت و اخوت کے جذبات نہیں ہیں.پس دانستہ یا نا دانستہ وہ
اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ کسی ایسے فعل میں جو مسلمہ طور پر مستحسن سمجھا جاتا ہے وہ ان
لوگوں سے پیچھے نہ رہے جو خدا کے قائل ہیں.گویا مقابلہ کا خیال اور بدنامی کا ڈراس
سے یہ کام کرواتے ہیں.مگر ظاہر ہے کہ اس صورت میں اس کے اندر کبھی بھی یہ جذبات
اعلیٰ اور اکمل صورت میں ظاہر نہیں ہو سکتے اور وہ بے لوث اور بے غرضانہ اور طبعی رنگ
پیدا نہیں ہوسکتا جو ایک خدا پر ایمان لانے والے شخص میں پایا جاتا ہے.اس کی محبت
ایسی ہی محبت ہوتی ہے جیسا کہ ایک سوتیلی ماں اپنے خاوند کو خوش کرنے کے لئے یا محلہ
والوں میں بدنامی سے بچنے کے لئے اپنے خاوند کی فوت شدہ بیوی کے بچوں سے کرتی
ہے.مگر دیکھنے والے سمجھ سکتے ہیں کہ کجا ماں کی طبعی محبت جو ایک قدرتی چشمہ کے طور پر
اس کے سینہ میں اُبلتی رہتی ہے اور کجا سوتیلی ماں کا ظاہر داری کا سلوک!
والشا ذ کالمعدوم.دوسری وجہ یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کی طرح دہر یہ بھی اس بات کو
سمجھتا اور محسوس کرتا ہے کہ نسلِ انسانی کی ترقی و بہبودی اور سوسائٹی کے قیام کے لئے یہ
ضروری ہے کہ لوگ آپس میں محبت اور سلوک سے رہیں اور باہم تعاون کا طریق اختیار
170
Page 171
کر کے ایسے کاموں میں حصہ لیں جو لوگوں کی جسمانی اور اخلاقی اور علمی اور قتصادی
بہبودی کا موجب ہیں.پس دُنیا کے ایک شہری ہونے کی حیثیت میں بھی ایک دہریہ
اس قسم کے خیالات اور جذبات پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس قسم کے کاموں میں
دلچسپی لیتا ہے.لیکن ظاہر ہے کہ یہ صورت بھی ایک ضابطہ اور معاملہ کا رنگ رکھتی ہے اور
و طبعی اور جذباتی رشتہ پیدا نہیں کرسکتی جو ایمان باللہ کا عقیدہ پیدا کرتا ہے.اور ایسا شخص
جو محض اس بنا پر ہمدردی خلق اللہ کے خیالات پیدا کرتا ہے کبھی بھی اس شخص کے مقام کو
نہیں پہنچ سکتا جو اس لئے نسلِ انسانی کے ساتھ محبت اور اخوت کے تعلقات رکھتا ہے کہ
بوجہ ایک خدا کی مخلوق ہونے کے یہ جذبہ اس کی فطرت کا حصہ ہے.گویا جہاں خدا کا
خیال فطری اور طبعی طور پر یہ جذبات انسان کے دل میں پیدا کرتا ہے وہاں یہ دوسری قسم
کے خیالات جو سوچ بچار کے نتیجہ میں پیدا ہوتے ہیں محض ضابطہ اور معاملہ کے رنگ میں
انسان کو اس طرف متوجہ کرتے ہیں.پس فرق ظاہر ہے.خلاصہ کلام یہ ہے کہ دہریہ کے دل میں نسل انسانی کی ہمدردی کے خیالات جن
وجوہات سے پیدا ہوتے ہیں وہ اُسے قطعاً اس اعلیٰ اور اشرف مقام تک نہیں پہنچا سکتے
جو ایمان باللہ کے نتیجہ میں انسان کو حاصل ہوسکتا ہے.علاوہ ازیں یہ بھی یادرکھنا چاہئے
کہ یہ جو باقی وجوہات ہمدردی اور محبت کے خیالات پیدا کرنے کی موجب ہیں یہ عام
ہیں جن سے ایک مومن باللہ بھی اسی طرح فائدہ اُٹھا سکتا ہے جس طرح کہ ایک دہر یہ
اُٹھاتا ہے لیکن ایمان باللہ کے نتیجہ میں جو جذبات پیدا ہوتے ہیں وہ صرف مومنوں کے
ساتھ مخصوص ہیں جن سے ایک دہر یہ کسی صورت میں بھی متمتع نہیں ہوسکتا اور ظاہر ہے
کہ جہاں بہت سے اسباب کسی نتیجہ کے پیدا کرنے میں مجموعی طور پر اثر ڈالیں گے
وہاں لا ز ما نتیجہ زیادہ اکمل اور اتم صورت میں ظاہر ہوگا پس اس لحاظ سے بھی خدا کا
عقیدہ بہر حال مفید اور نفع بخش ٹھہرتا ہے.171
Page 172
اس کے علاوہ یہ بات بھی یاد رکھنی چاہئے کہ اور جتنے بھی موجبات وحدت ہیں وہ
گو ایک حد تک تعاون اور ہمدردی اور قربانی کی رُوح پیدا کر دیں، لیکن اخوت انسانی کا
جذ بہ وہ کسی صورت میں بھی پیدا نہیں کر سکتے کیونکہ اخوت کا جذبہ یعنی یہ خیال کہ سب
انسان بھائی بھائی ہیں سوائے اس کے اور کسی صورت میں پیدا نہیں ہوسکتا کہ انسان کے
او پر ایک واحد خالق و مالک و آقا کے وجود کو تسلیم کیا جائے کیونکہ اخوت کے معنے ہی یہ
ہیں کہ ہم سب ایک منبع سے نکلی ہوئی ہستیاں ہیں.لہذا اور اسباب خواہ کتنی بڑی حد تک
بھی افراد و اقوام کے درمیان تعاون و ہمدردی کارشتہ پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں
لیکن ان کے نتیجہ میں اخوت کا جذبہ کبھی بھی پیدا نہیں ہوسکتا.پس اس لحاظ سے بھی
ایمان باللہ کی ضرورت اور اس کا مفید ہونا ثابت ہے.ظاہر ہے کہ جب تک نسلِ انسانی
میں اخوت اور وحدت کا جذبہ فطری طور پر پیدا نہ ہو جائے اس وقت تک ان کا ظاہری
اتحاد اور تعاون اس قابل نہیں ہوتا کہ اس پر کوئی اعتماد کیا جا سکے بلکہ اس صورت میں ہر
وقت اس بات کا اندیشہ رہے گا کہ جب کبھی بھی ذرا کسی کی مرضی کے خلاف کوئی بات
ہوگی تو فوراً خود غرضی کے خیالات غالب آ کر بغض و عداوت کا رنگ پیدا کر دینگے.دنیا
کا امن یقیناً اس وقت تک سخت خطرہ میں ہے جب تک کہ لوگ ایک زندہ حقیقت کے
طور پر اپنے اندر یہ ایمان قائم نہ کر لیں کہ ہمارے اوپر ایک واحد خدا ہے جو ہمارا خالق و
مالک ہے اور اس لئے ہم سب کو بھائی بھائی بن کر رہنا چاہئے اور اگر کبھی ہمارے اندر
اختلاف بھی پیدا ہوتو ہمیں انصاف کو ہاتھ سے نہ دینا چاہئے بلکہ ایک دوسرے کی خاطر
قربانی اور ایثار کا طریق اختیار کرنا چاہئے.دراصل غور سے دیکھا جائے تو ضابطہ اور
معاملہ کے تعلقات محض خود غرضی پر مبنی ہوتے ہیں کیونکہ انسان محسوس کرتا ہے کہ اگر میں
دوسروں کے ساتھ اچھے تعلقات نہ رکھونگا تو دوسرے بھی میرے ساتھ اچھی طرح پیش
نہ آئیں گے اور اس طرح میرے مفاد کو نقصان پہنچے گا.اور اس لئے خود حفاظتی کے طور
172
Page 173
پر وہ حسنِ سلوک کا طریق اختیار کرتا ہے اور دوسروں کے ساتھ اس لئے ہمدردی اور
تعاون کا برتاؤ کرتا ہے تا کہ اُس کے نتیجہ میں لوگ بھی اس کے ساتھ ہمدردی اور تعاون کا
طریق اختیار کریں.اور ہر چند کہ اس صورت کا نتیجہ بھی ایک حد تک مفید اور نفع بخش ہی
ہوتا ہے لیکن ظاہر ہے کہ ایک خود غرضانہ صورت کو اس اعلیٰ اور اشرف مقام سے کچھ بھی
نسبت نہیں کہ جس میں ایک طبعی اور فطری جذبہ کے طور پر لوگوں کے درمیان
اخوت و وحدت کے خیالات پیدا ہوتے ہیں اور یہ فطری جذ بہ جو اخوت کی صورت میں
ظاہر ہوتا ہے بغیر ایمان باللہ کے ہرگز حاصل نہیں ہوسکتا.کیا مذہب دنیا میں جنگ وجدال کا موجب ہے؟
پیشتر اس کے کہ میں ایمان باللہ کا دوسرا فائدہ بیان کروں ایک شبہ کا ازالہ
ضروری ہے جو بعض لوگوں کی طرف سے پیدا کیا جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ دُنیا میں مذہب
کا وجود باہم جنگ وجدال اور فتنہ وفساد اور فرقہ بندیوں کا موجب ہے.کیونکہ مذہب
انسان کے اندر تنگ خیالی اور کم حوصلگی پیدا کرتا ہے جودُ نیا میں قیام امن اور نسل انسانی
کی ترقی و بہبودی کے لئے سم قاتل ہے اس لئے لوگوں کو مذہب کی قیود سے آزاد
ہونے کی کوشش کرنی چاہئے تا کہ وسعت خیالی پیدا ہو اور لوگ آپس میں محبت اور امن
کے ساتھ رہ سکیں اور چونکہ مذہب خدا کے خیال کے نتیجہ میں پیدا ہوتا ہے اس لئے ہمیں
ساتھ ہی ایسے خدا کو بھی خیر باد کہنا چاہئے جس کا خیال دنیا میں فتنہ وفساد کا باعث ہے.یہ وہ اعتراض ہے جو آجکل کے نو تعلیم یافتہ طبقہ کی طرف سے کیا جاتا ہے اور جس پر
یورپ کے مدبرین بھی بہت زور دیتے ہیں.لیکن اگر ہم ذرا غور سے کام لیں تو یہ بات
مخفی نہیں رہتی کہ یہ اعتراض محض قلت تذبر کے نتیجہ میں پیدا ہوا ہے.مگر اصل جواب
دینے سے قبل میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اس اعتراض کو درست بھی مان لیں یعنی
173
Page 174
اس بات کو تسلیم بھی کرلیں کہ واقعی مذہب کا وہی نتیجہ ہے جو بیان کیا جاتا ہے پھر بھی اس
سے خدا کے موجود ہونے کے خلاف کوئی استدلال نہیں ہوسکتا.یعنی اس سے یہ ثابت
نہیں ہوسکتا کہ اس دُنیا کا کوئی خالق نہیں ہے بلکہ اس سے زیادہ سے زیادہ یہ ثابت
دُنیا
ہو سکے گا کہ خدا کا عقیدہ تنگ خیالی اور امن شکنی کا موجب ہے.لیکن اگر واقعی کوئی خدا
موجود ہے تو پھر اُس کا ماننا خواہ کچھ بھی نتیجہ پیدا کرے ہمیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ہم
اسکے موجود ہونے سے ہی انکار کر دیں.پس اگر خدا کا موجود ہونا ثابت ہے تو پھر خواہ
مذہب فتنہ وفساد کا ہی موجب ہو ہم خدا کے موجود ہونے سے انکار نہیں کر سکتے.لیکن حق
یہ ہے کہ یہ بات ہی غلط اور باطل ہے کہ مذہب فتنہ وفساد کا موجب ہوتا ہے اور جن
لوگوں نے ایسا نتیجہ نکالا ہے انہوں نے خطر ناک غلطی کھائی ہے.ہم ابھی ابھی یہ ثابت کر چکے ہیں کہ خدا کا خیال طبعا اور فطر تا لوگوں کے دلوں
میں باہم محبت و اخوت کے جذبات پیدا کرتا ہے اور تمام قومی اور ملکی اور نسلی تعصبات کو
مٹاکر ایک عالمگیر اخوت انسانی کا خیال قائم کرنے کا موجب ہے بلکہ ایمان باللہ کے
بغیر اس عالمگیر اخوت کا خیال پیدا ہونا ہی ناممکن ہے.پس یہ کس طرح ہوسکتا ہے کہ خدا
کا عقیدہ فتنہ وفساد اور تنگ خیالی کا موجب ہو؟ فتنہ وفساد اور تنگ خیالی کے پیدا ہونے کو
ہرگز کوئی طبعی تعلق خدا کے خیال سے نہیں ہے اور عقلِ انسانی ایک لمحہ کے لئے بھی اس
بات کو قبول نہیں کر سکتی کہ خدا کے خیال کا نتیجہ ہاں ایسے خدا کے خیال کا نتیجہ جسے انسان
کوئی قومی یا ملکی یا نسلی خدا نہ سمجھتا ہو بلکہ تمام بنی نوع آدم کا مشتر کہ خالق و مالک خدا قرار
دیتا ہو تنگ خیالی اور تعصبات قومی اور جنگ وجدال اور فرقہ بندی کی صورت میں ظاہر
ہوسکتا ہے.کوئی صحیح الدماغ شخص ان دو باتوں میں سبب اور مستقب کا کوئی طبعی رشتہ
دریافت نہیں کر سکتا.پس اگر واقعی مذاہب کا وجود فتنہ وفساد اور تنگ خیالی اور تعصبات ملی
کا موجب ہے تو ہمیں کسی دوسری جگہ اس کا سبب تلاش کرنا چاہئے اور غور کرنا چاہئے کہ
174
Page 175
ایسا کیوں ہوتا ہے نہ یہ کہ سراسر ظلم اور تعدی کے ساتھ اور بالکل غیر طبعی طور پر ہم اسے
خدا کے عقیدہ کی طرف منسوب کر دیں.بات یہ ہے کہ بد قسمتی سے اعتراض کرنے والوں کے سامنے مذاہب کی ایسی
حالت پیش ہوئی ہے کہ جس میں سوائے مذہب کے نام کے اور کچھ نہیں.یہ اعتراض
موجودہ زمانہ کا مخصوص اعتراض ہے اور بدقسمتی سے اس زمانہ میں تمام مذاہب کے
متبعین اپنے مذاہب کی حقیقت سے دُور پڑے ہوئے ہیں اور کوئی ایک مذہب بھی ایسا
نظر نہیں آتا کہ جس کے پیرو اپنے مذہب کی حقیقت پر قائم ہوں بلکہ خود مذاہب کی
شکل وصورت انسانی دست برد سے بُری طرح مسخ ہو چکی ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آزاد
طبع لوگوں کو مذاہب پر اعتراض کرنے کا موقعہ مل گیا ہے.حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ دُنیا
میں قیام امن اور نسل انسانی کی دماغی تنویر کے لئے مذہب سب ذرائع میں سے بڑا
ذریعہ ہے اور جب کبھی بھی لوگ مذہب کی حقیقت پر قائم ہوئے ہیں فتنہ وفساد اور بے جا
جنگ وجدال کے خیالات ان میں سے مٹنے شروع ہو گئے ہیں اور وسعت خیالی اور
عالی حوصلگی پیدا ہونی شروع ہوگئی ہے.کسی مذہب کی تاریخ کو دیکھو اور اس کے اس
زمانہ کو لے لو جس میں اس کے متبعین اس مذہب کی حقیقت پر قائم نظر آتے ہیں اور پھر تم
دیکھو گے کہ وہ لوگ کیسے عالی حوصلہ اور وسیع خیال اور ہمدرد بنی نوع انسان اور امن اور
صلح کے خواہاں نظر آتے ہیں اور پھر اس کے مقابل میں اس مذہب کی تاریخ کے اس
زمانہ کولو جس میں اس کے متبعین اپنے مذہب کی حقیقت سے دور ہو گئے ہوں اور محض
اہمی اور رسمی طور پر مذہب کی طرف منسوب ہوتے ہوں تو تم دیکھو گے کہ تمہیں اس کے
متبعین میں تنگ خیالی، کم حوصلگی، بیجا تعصبات ملتی ، چھوٹے چھوٹے اختلافات پر لڑنے
جھگڑنے کا خیال اور امن شکنی کی طرف میلان نظر آئے گا.میں یہ دعوی بلا خوف تردید
کرتا ہوں اور ہر مذہب و ملت کے متعلق کرتا ہوں اور میں یقین رکھتا ہوں کہ جو کوئی
175
Page 176
بھی دیانتداری کے ساتھ اس مسئلہ میں تاریخی تحقیق کرے گا وہ اس نتیجہ پر پہنچے گا جو میں
نے اس جگہ بیان کیا ہے.میں بفضلہ تعالیٰ ایک مسلمان ہوں اور آنحضرت صلعم
(فداہ نفسی) کے ادنی ترین خادموں میں اپنے آپ
کو شمار کرنا اپنے لئے سب فخروں سے
بڑھ کر فخر سمجھتا ہوں مگر میں اس افسوس ناک اعتراف کے بغیر نہیں رہ سکتا کہ آجکل
دوسری قوموں کی طرح مسلمان کہلانے والے بھی اس خطرناک اور مہلک مرض میں مبتلا
ہیں کہ جو تنگ خیالی کے نام سے موسوم ہے اور بے جا تعصبات ملی نے ان کی انسانیت
کے اعلیٰ اور اشرف جذبات کو مغلوب کر رکھا ہے اور بات بات میں جھگڑ نا اور لڑ نا اور
بیہودہ اختلافات پیدا کر کے امن شکنی کی طرف مائل ہو جانا ان کی عادت میں داخل ہو گیا
ہے.مگر کیا یہ اسلام کا قصور ہے؟ ہر گز نہیں.جب مسلمان اسلام پر قائم تھے اور اسلامی
روح ان کے اندر زندہ تھی اس وقت ان کے اندر یہ باتیں نہ تھیں بلکہ اس وقت وہ ایک
روشن خیال وسیع حوصلہ بنی نوع آدم کی خیر خواہ اور ہمدردامن پسند صلح جو اور دوسروں کی
خاطر قربانی اور ایثار دکھانے والی قوم تھے جس نے اپنے عالمگیر نور کی کرنوں سے دُنیا بھر
میں اُجالا کر رکھا تھا مگر اب اس عالیشان عمارت کے کھنڈرات ہیں اور ہم ہیں !
اسی طرح دوسری قوموں کا حال ہے.عیسائیت جب شروع شروع میں قائم
ہوئی تو اس کے متبعین نے قربانی و ایثار اور بنی نوع انسان کی ہمدردی کا بہت اچھا نمونہ
دکھایا اور امن پسندی اور صلح جوئی کا طریق رکھا لیکن جب مسیحی لوگ عیسائیت کی اصل
تعلیم اور صیحی رُوح سے دُور جا پڑے تو پھر انہوں نے بھی دُنیا میں ظلم و ستم ، کشت وخون
اور بیجا تعصبات مذہبی کا وہ طوفان برپا کر دیا کہ الامان! چنانچہ ریفر میشن
(Reformation) کے زمانہ کی تاریخ ہمارے اس دعویٰ کا کافی ثبوت ہے اور غالبًا
کسی قوم کے حالات میں ایسی تنگ خیالی اور بے جا تعصبات اور امین شکنی اور
قتل و غارت کا منظر نظر نہیں آتا جو کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے نام نہاد متبعین نے
176
Page 177
ریفرمیشن کے زمانہ میں دکھایا.ہندو اور سکھ اور دوسرے مذاہب کی تاریخیں بھی کم و بیش یہی نظارہ ہمارے
سامنے پیش کرتی ہیں بلکہ بعض لحاظ سے ہندوؤں اور سکھوں میں یہ منظر زیادہ بھیانک
صورت میں نظر آتا ہے.اور یہ سب مثالیں اس بات کو ثابت کر رہی ہیں کہ در حقیقت جو
الزام مذہب پر لگایا جاتا ہے وہ مذہب پر نہیں پڑتا بلکہ وہ مذہب کی رُوح سے دُور
جاپڑنے کا نتیجہ ہے.لیکن چونکہ بدقسمتی سے اس
زمانہ کی تمام اقوامِ عالم مذہب کی رُوح
کو ضائع کر چکی ہیں اس لئے جلد باز اور کوتہ بین نکتہ چینوں کو یہ اعتراض کرنے کا اچھا
موقعہ مل گیا ہے کہ مذہب تنگ خیالی اور امن شکنی پیدا کرتا ہے.اسی لئے خدا وند قدوس نے جو دنیا کو ضلالت کے تاریک گڑھے میں پڑا ہو انہیں
دیکھنا چاہتا کمال شفقت اور مہربانی سے اپنے ایک پاک بندہ حضرت مرزا غلام احمد
صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی معہود کو اس زمانہ میں ہدایت خلق کے لئے مبعوث
فرمایا ہے تاکہ تمام وہ اعتراضات جو مذہب کی طرف منسوب ہونے والے لوگوں کی
بداعمالی کی وجہ سے مذہب پر پڑتے تھے اور اس طرح مخلوق خدا کو خدا کی طرف سے
بدگمان کرنے کا موجب ہورہے تھے اور مذہب میں تشد داور جبر اور تنگ نظری کا رستہ
کھولتے تھے ان کا ازالہ ہو اور لوگ اپنے آسمانی آقا و مالک کو پہچان کر پھر بھائی بھائی
بن جائیں.مگر افسوس ہے کہ لوگوں نے اس مصلح ربانی کے خادموں اور اس آسمانی
ہدایت کے شمع برداروں کے ساتھ بھی وہی جاہلانہ اور متعصبانہ طریق اختیار کر رکھا ہے
جو ان لوگوں کی قدیم عادت اور شیوہ ہے.چنانچہ کابل میں کئی بے گناہ احمدی محض احمدی
ہونے کی وجہ سے نہایت ظالمانہ طور پر سنگسار کر دیئے گئے اور اس طرح خود مسلمان
کہلانے والوں نے غیروں کو اسلام پر یہ اعتراض کرنے کا موقعہ دے دیا کہ اسلام جبر و
تشد داور تنگ خیالی اور بے جا تعصب اور ظلم وستم کی تعلیم دیتا ہے.افسوس ! صد افسوس!
177
Page 178
کسی شاعر نے سچ کہا ہے.من
از
بیگانگاں ہرگز
نه نالم
که با من هرچه
کرد آن آشنا کرد
خلاصہ کلام یہ کہ مذہب کے متعلق ایسا خیال کرنا کہ وہ تنگ نظری اور
جنگ وجدال کا باعث ہے صرف موجودہ زمانہ کی حالت کے نتیجہ میں پیدا ہوا ہے والا
اگر مذاہب عالم کی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات اظہر من الشمس ہو کر نظر آتی ہے
کہ جب کبھی بھی لوگ مذہب کی اصل روح اور حقیقت پر قائم ہوئے ہیں ان کے اندر
دوسروں کی نسبت زیادہ وسعت خیالی اور روشن دماغی اور امن پسندی اور قربانی
اور برداشت کا مادہ پیدا ہو گیا ہے اور تعلیم کے لحاظ سے بھی دیکھیں تو تفاصیل کو الگ رکھ
کر کوئی مذہب بھی ایسا نظر نہیں آتا جو اُصولی طور پر امن پسندی اور صلح جوئی اور
وسعت حوصلگی کی تلقین نہ کرتا ہو.پس تنگ خیالی اور فتنہ و فساد کا مادہ اس تعلیم کو بھلا دینے
کا نتیجہ تو ہوسکتا ہے مگر تعلیم پر کار بند ہونے کا نتیجہ ہر گز نہیں ہوسکتا.دوسرا جواب جو میں اس شبہ کا دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر غور کیا جائے تو یہ
بات عقلاً بھی محال نظر آتی ہے کہ کوئی ایسا شخص جو مذہب کی حقیقت اور غرض و غایت کو
سمجھتا ہو تنگ خیالی اور فتنہ وفساد کا مرتکب ہو سکے.مذہب کا مفہوم ملک یا قوم کی طرح
نہیں جو جغرافیہ کی حدود یا نسلی قیود میں محصور ہو اور اس کا حلقہ وسیع نہ کیا جا سکے بلکہ
مذہب ان عقائد اور خیالات اور ضابطہ عمل کا نام ہے جو کوئی شخص حقوق اللہ اور
حقوق العباد کے متعلق رکھتا ہے اور جسے وہ حق سمجھ کر دوسروں تک بھی وسیع کرنے کی
کوشش کرتا ہے.پس مذہب ایک کھلے دروازوں والی عمارت ہے جس کے اندر ہر شخص
خواہ وہ کسی قوم یا کسی ملک سے تعلق رکھتا ہو داخل ہوسکتا ہے.بلکہ جس کے اندر داخل
ہونے کی دعوت ہر مذہبی شخص دوسروں کو دیتا ہے.اندریں حالات کوئی شخص جو حقیقی طور
178
Page 179
پر مذہب کی غرض کو پورا کرنا چاہتا ہے کسی صورت میں بھی تنگ خیالی یا فتنہ وفساد کا مرتکب
نہیں ہوسکتا بلکہ برخلاف اس کے ایسے شخص کی یہ انتہائی کوشش ہوگی کہ وہ اپنے
حُسنِ اخلاق اور پُر امن تبلیغ و تلقین سے دوسروں
کو اپنا ہم خیال بنائے اور کسی ایسی بات کا
مرتکب نہ ہو جو لوگوں کے لئے اس کا مذہب پسند کرنے کے رستہ میں روک ہو جائے.پس یہ قطعاً محال ہے کہ کوئی شخص جو مذہب کی حقیقت پر قائم ہے اور مذہب کی غرض
وغایت کو سمجھتا ہے تنگ خیالی اور فتنہ و فساد کا مرتکب ہو.تیسرا جواب اس اعتراض کا یہ ہے کہ اگر بعض اوقات مذہب جنگ وجدال کا
موجب ہوتا ہے تو کیا اور چیزیں اس کا موجب نہیں ہوتیں؟ دُنیا میں بیسیوں باتیں ایسی
ہیں کہ جو اقوام و افراد کے درمیان جنگ اور فساد کا موجب ہو جاتی ہیں تو کیا اس وجہ
سے ان سب کو ترک کر دیا جائے گا ؟ ملکی اور سیاسی اختلافات.قومی سوالات.تجارتی
اور اقتصادی امور وغیرہ وغیرہ بیسیوں اس قسم کی باتیں ہیں کہ جو اقوام عالم کے درمیان
جنگ و جدال کا باعث ہو جاتی ہیں.اور اسی طرح افراد کے درمیان فتنہ و فساد کے پیدا
ہو جانے کے بھی سینکڑوں موجبات ہیں جن سے کوئی عقلمند شخص انکار نہیں کرسکتا تو کیا ان
سب باتوں کو صرف اس وجہ سے چھوڑ دیا جائے گا کہ کبھی کبھی ان کی وجہ سے
امن شکنی ہو جاتی ہے؟ اگر ایسا کیا جائے تو اس کے یہ معنے ہونگے کہ زندگی کے تمام
شعبوں کو ترک کر کے ہر شخص رہبانیت اختیار کر لے تا کہ نہ دوسروں کے ساتھ معاملہ
پڑے اور نہ کوئی اختلاف و انشقاق کی صورت پیدا ہو.تاریخ عالم پر نظر ڈالو.دُنیا کی بیشتر جنگیں ایسی گذری ہیں کہ جن کا باعث مذہبی
اختلاف ہرگز نہ تھا بلکہ کسی جگہ ملکی یا سیاسی اختلاف تھا اور کسی جگہ کوئی قومی سوال پیدا
ہو گیا تھا اور کسی جگہ کوئی اقتصادی اور تجارتی امر در پیش تھا اور کسی جگہ کوئی اور اسی قسم کی وجہ
تھی.ابھی جو یہ گذشتہ جنگ یورپ میں بلکہ ساری دنیا میں وقوع میں آئی ہے اس میں
179
Page 180
ہرگز کوئی مذہبی سوال نہ تھا بلکہ محض سیاسی بنا پر یہ سارا گشت وخون وقوع میں آیا اور یہ
گشت وخون بھی ایسا تھا کہ جو اپنی وسعت اور تباہی کے لحاظ سے دُنیا کی تاریخ میں اپنی
نظیر نہیں رکھتا.اب سیاست بھی چھوڑ دو کیونکہ وہ بعض اوقات جنگ کا موجب ہو جاتی
ہے.میرے عزیزو! یہ سب نادانی اور جہالت کی باتیں ہیں.مذہب کو ہرگز کوئی
خاص رشتہ تنگ خیالی یا جنگ و جدال سے نہیں ہے بلکہ جس طرح دُنیا میں اور اور باتیں
اقوام و افراد کے درمیان امن شکنی کا موجب ہو جاتی ہیں اسی طرح ( گودرجہ میں ان
سے بہت کم ) کبھی کبھی مذہبی اختلاف بھی اس کا موجب ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی مذہب
میں یہ خصوصیت ہے کہ وہ صرف اُسی وقت اس کا موجب ہوتا ہے کہ جبکہ لوگ مذہب کی
حقیقت سے دُور جاپڑتے ہیں.جیسا کہ مثلاً ہمارے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
زمانہ میں یہود اور مشرکین عرب نے مذہب کی حقیقت کو نہ سمجھتے ہوئے محض ظلم اور تعدی
کے طور پر بیگناہ مسلمانوں کے خلاف جنگ برپا کر دی اور پھر مسلمانوں کو بھی خود حفاظتی
اور قیام امن کی غرض سے تلوار کا جواب تلوار سے دینا پڑا اور اس طرح ملک میں جنگ کی
صورت پیدا ہوگئی جس کے ذمہ وار کلیتہ مذہب کی حقیقت اور غرض و غایت کو نہ سمجھنے
والے مشرکین و یہود تھے اور مسلمانوں کی طرف سے یہ جنگ صرف قیامِ امن کی غرض
سے تھی.الغرض یہ ایک نہایت لغو اور بیہودہ خیال ہے کہ مذہب جنگ اور فتنہ و فساد کا
موجب ہوتا ہے.بلکہ حق یہ ہے کہ مذہب ہی وہ طاقت ہے جو کما حقہ فتنہ وفساد کا
سد باب کر سکتی ہے اور مذہب کی حقیقت سے دُور ہونا امن شکنی اور فتنہ کا باعث ہو جاتا
ہے.لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر بفرض محال یہ مان بھی لیا جائے کہ مذہبی اختلافات
جنگ وجدال کا موجب ہوتا ہے تو پھر بھی معترضین کو یہ حق نہیں کہ اس بنا پر مذہب سے
180
Page 181
روگردانی کریں کیونکہ جیسا کہ اوپر بیان کیا جاچکا ہے دنیا میں بہت سی اور باتیں بھی
امن شکنی اور جنگ وجدال کا موجب ہوتی رہتی ہیں مر کوئی منظمند انسان ایسا نہیں جو اس
وجہ سے اُن کے ترک کرنے کا خیال دل میں لائے.در حقیقت بات یہ ہے کہ ہر
اختلاف جس کا غلط استعمال کیا جائے بدنتائج پیدا کرے گا اور اس میں مذہب کی قطعاً
کوئی خصوصیت نہیں.سیاسی اور ملکی اختلافات کا غلط استعمال جنگ پیدا کرے گا.قومی
اختلافات کا غلط استعمال جنگ پیدا کرے گا.تجارتی اور اقتصادی اختلافات کا غلط
استعمال جنگ پیدا کرے گا.اسی طرح مذہبی اختلافات کا غلط استعمال بھی جنگ پیدا
کرے گا.فرق صرف یہ ہے کہ باقی باتیں گو غلط استعمال میں آنے سے امن شکنی کا
موجب تو ہو جاتی ہیں لیکن اُن
کا صحیح استعمال خاص طور پر قیام امن اور باہم تعاون اور
اخوت کے جذبات پیدا کرنے کا موجب نہیں ہوتا.لیکن مذہب جبکہ وہ اپنی اصلی
شکل وصورت میں رہے اور لوگ اس کا صحیح استعمال کر یں خصوصیت کے ساتھ امن
اور تعاون اور وحدت اور اخوت اور ہمدردی کے جذبات پیدا کرتا ہے.حق یہی ہے
چا ہوتو قبول کرو.چوتھا جواب اس شبہ کا یہ ہے کہ معترضین نے مذہب کے معنے سمجھنے میں بھی غلطی
کھائی ہے.انہوں نے غالباً یہ سمجھ رکھا ہے کہ مذہب صرف خدا کے عقیدہ کا نام ہے اور
جب کسی نے یہ عقیدہ ترک کر دیا تو اُس نے گویا مذہب کو چھوڑ دیا.گویا انہوں نے یہ سمجھ
رکھا ہے کہ مذہب ایک ایسی چیز ہے جسے انسان چھوڑ بھی سکتا ہے.حالانکہ گو عرفی طور پر
خدا کے عقیدہ کا تارک لامذہب کہلاتا ہے ،لیکن اگر مذہب کے معنوں پر غور کیا جائے تو
پتہ لگتا ہے کہ مذہب انسانی زندگی کا ایک ضروری حصہ ہے اور کسی انسان کے لئے یہ قطعاً
ناممکن ہے کہ مذہب کی قید سے مطلقاً آزاد ہو سکے.کیونکہ درحقیقت مذہب ان
خیالات وعقائد اور طریق عمل کا نام ہے جو انسان موت وحیات کے متعلق اپنی زندگی
181
Page 182
میں اختیار کرتا ہے.اور ظاہر ہے کہ اس مفہوم کے لحاظ سے کسی شخص کا مذہب سے الگ
ہونا محالات عقلی میں سے ہے کیونکہ ہر شخص کوئی نہ کوئی طریق زندگی رکھتا ہے.پس یہ
سوال تو پیدا ہوسکتا ہے کہ ہم یہ مذہب پسند نہیں کرتے یا وہ مذہب پسند نہیں کرتے لیکن
یہ بات کہ انسان مطلقاً مذہب سے آزاد ہو جائے قطعاً ناممکن ہے.جب تک انسان
زندہ ہے اُسے فلسفہ موت وحیات کے متعلق کچھ خیالات وعقائد رکھنے پڑینگے اور اپنے
اعمال و افعال میں کوئی طریق اختیار کرنا پڑے گا اور یہی خیالات و عقائد اور طریق عمل
اس کا مذہب کہلائے گا.زیادہ سے زیادہ کوئی شخص یہ کر سکتا ہے کہ جو معروف الہامی
مذاہب ہیں ان سے منحرف ہو جائے اور اپنے لئے خود اپنے دماغ سے کوئی نیا طریق
نکال لے لیکن ایسا شخص مذہب کی اس تعریف کے لحاظ سے جو ابھی ہم نے بیان کی ہے
حقیقتالا مذہب نہیں کہلا سکتا بلکہ جوطریق بھی وہ اپنے لئے پسند کرے گا وہی اس کا مذہب
ہوگا.اگر کوئی شخص خدا کو مانتا ہے تو یہ اس کا مذہب ہے اور اگر انکار کرتا ہے تو یہ بھی اس
کے مذہب کا حصہ ہے.الغرض مذہب زندگی کے طریق عمل اور ان عقائد و خیالات کا
نام ہے جو انسان اختیار کرتا ہے.اور ظاہر ہے کہ ان معنوں کے لحاظ سے مذہب سے
آزاد ہونا کسی شخص کے لئے ممکن نہیں.تم اسلام سے آزاد ہو سکتے ہو،عیسائیت سے آزاد
ہو سکتے ہو، ہندو ازم سے آزاد ہو سکتے ہو، بدھ ازم سے آزاد ہو سکتے ہو اور ہر دوسرے
معروف الہامی مذہب سے آزاد ہو سکتے ہو لیکن مطلقا مذ ہب سے آزاد نہیں ہو سکتے بلکہ
بہر حال تمہیں کوئی نہ کوئی مذہب ضرور رکھنا پڑے گا خواہ وہ تمہارے اپنے دماغ کا ہی بنایا
ہوا کیوں نہ ہو.تم خدا کو یا تو مانو گے یا انکار کرو گے.اگر مانو گے تو اس کی کوئی نہ کوئی
صفات بھی تسلیم کرو گے.اگر انکار کرو گے تو اس عالم کی ابتداء اور حیات کے آغاز کے
متعلق تمہیں کوئی نہ کوئی عقیدہ قائم کرنا پڑے گا.پھر مختلف لوگوں یعنی دوست ، دشمن،
رشتہ دار، غیر رشته دار، خاوند، بیوی، خادم، آقا، بادشاہ، رعایا وغیرہ وغیرہ کے ساتھ معاملہ
182
Page 183
کرنے میں تمہیں کوئی نہ کوئی طریق عمل اختیار کرنا ہوگا اور یہی خیالات اور یہی
طریق عمل تمہارا مذ ہب کہلائے گا.خلاصہ کلام یہ کہ مذہب زندگی کے ساتھ لازم وملزوم
کے طور پر لگا ہوا ہے اور کوئی شخص مذہب کی قید سے مطلقاً آزادنہیں ہوسکتا اور یہ جو بعض
اوقات کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص لا مذہب ہے اس کے صرف یہ معنے ہوتے ہیں کہ وہ کسی
معروف الہامی مذہب کا پیرو نہیں بلکہ اُس نے اپنا مذہب خود آپ بنایا ہو ا ہے ورنہ حقیقتاً
کوئی شخص بھی لا مذہب نہیں ہوتا.اب جب یہ بات ظاہر ہوگئی کہ مذہب کی قید سے آزاد ہونا ناممکنات سے ہے تو
پھر معترضین کا یہ اعتراض کہ چونکہ مذہب جنگ وجدال اور تنگ خیالی پیدا کرتا ہے اس
لئے انسان کو اس سے آزاد ہو جانا چاہیئے ایک لایعنی بلکہ مضحکہ خیز بات قرار پاتی ہے جو
کسی عظمند کے منہ پر نہ آنی چاہئے.اور اگر یہ کہا جائے کہ اس اعتراض سے مراد یہ ہے
کہ انسان کو معروف الہامی مذاہب سے آزاد ہو جانا چاہئے تو یہ ایک جہالت کی بات
ہوگی کیونکہ یہاں یہ بحث نہیں کہ فلاں مذہب فتنہ و فساد پیدا کرتا ہے بلکہ سوال یہ ہے کہ
مطلق مذہب فتنہ وفساد کا موجب ہے والا اگر کوئی خاص مذہب واقعی فتنہ اور امن شکنی کا
موجب بنتا ہے تو ہم کب کہتے ہیں کہ اُسے اختیار کرو.ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ یہ
بات غلط ہے کہ مطلقاً مذہب فتنہ اور جنگ کا موجب ہے اور اگر یہ بات درست بھی ہو تو
پھر بھی چونکہ ہم کسی صورت میں بھی مذہب سے آزاد نہیں ہو سکتے اس لئے مذہب سے
آزاد ہونے کا سوال اُٹھانا ہی فضول اور لغو ہے.علاوہ ازیں اگر بفرض محال لوگ الہامی مذاہب کی پیروی سے آزاد بھی ہو جائیں
پھر بھی اُن کے اندر مذہبی خیالات موجود رہیں گے کیونکہ یہ بالکل قرین قیاس نہیں کہ ان
مذاہب سے آزاد ہو کر سب لوگ اپنے واسطے ایک سے خیالات وعقائد ایک سا
طریق عمل مقرر کر لیں.بلکہ اس صورت میں دُنیا میں مذاہب کی تعداد یقیناً موجودہ
183
Page 184
تعداد سے بھی بہت زیادہ بڑھ جائے گی.یعنی اب اگر دنیا میں صرف پانچ دس یا پندرہ
ہیں مذاہب پائے جاتے ہیں تو اس وقت غالباً ہزاروں لاکھوں مذاہب پیدا ہو جائیں
گے.اور کوئی تعجب نہیں کہ یہ تعداد کروڑوں تک جا پہنچے کیونکہ ہر شخص آزاد ہو کر اپنے لئے
اپنے مطلب کا مذہب بنانا چاہے گا اور ظاہر ہے کہ اس تعداد کی زیادتی کے ساتھ ہی
اختلافات کی کثرت بھی غیر معمولی طور پر ظاہر ہوگی جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اب اگر مذہبی
اختلاف گاہے گا ہے لڑائی جھگڑے کا موجب ہوتا ہے تو اس صورت میں آئے دن
مذہب کے نام پر فتنہ وفساد اور خون خرابہ ہو ا کرے گا.اور اگر یہ کہا جائے کہ فتنہ وفساد اور تنگ خیالی کا موجب صرف الہامی مذاہب
ہو سکتے ہیں جن کا مرکزی نقطہ خدا کی ذات اور قیامت اور جزا سزا کا عقیدہ ہیں.کیونکہ
ہر فرقہ اپنے آپ کو نجات یافتہ سمجھتا ہے اور دوسروں کو غیر ناجی اور جہنمی قرار دیتا ہے جس
کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف نفرت و حقارت کے جذبات پیدا ہوتے
ہیں.لیکن غیر الہامی مذاہب جو انسان خود اپنے لئے آپ سوچ کر بنا تا ہے وہ اس تفرقہ
اور با ہم نفرت و حقارت کا موجب نہیں ہو سکتے خصوصاً جبکہ خُدا کا خیال درمیان میں نہ
آئے اور نہ جزا سزا کا کوئی خیال ہو.تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ شبہ فطرتِ انسانی کے
بالکل خلاف ہے.دوسرے کو خطرہ کی حالت میں دیکھنے کا طبعی اور فطرتی نتیجہ یہ ہوتا ہے
کہ اس کے لئے ہمدردی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں اور اس کے بچانے کے واسطے
کوشش کا خیال دل میں آتا ہے اور یہ بالکل غیر طبعی ہے کہ ایسے موقع پر نفرت اور
حقارت کے خیالات پیدا ہوں.پس اگر مختلف فرقہ جات اپنے آپ کو ناجی اور دوسروں
کو غیر ناجی سمجھتے ہیں تو اس کا طبعی اور فطری نتیجہ یہ ہونا چاہئے کہ وہ دوسروں کے لئے
دردمند ہوں اور ان کو ہلاکت سے بچانے کے لئے اپنی پوری کوشش اور سعی سے کام لیں
اور اس صورت میں نفرت و حقارت وعداوت کا پیدا ہونا بالکل بیرون از سوال ہے.کیا
184
Page 185
اگر کوئی کسی کو اپنی آنکھوں کے سامنے دریا میں ڈوبتا ہوا دیکھے تو اس کے دل میں یہ خیال
پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ شخص قابل نفرت و حقارت ہے اور مجھے اس سے عداوت کرنی چاہئے
یا یہ کہ وہ فور پانی میں گو دکر اس کے بچانے کی کوشش کرے گا؟ اور اگر وہ شخص کنارے پر
کھڑا رہے گا اور اُس ڈوبتے ہوئے شخص کو بچانے کے لئے باوجود طاقت رکھنے کے
ہاتھ پاؤں نہ مارے گا بلکہ الٹا خوش ہو گا اور ڈوبنے والے کو قابلِ نفرت و حقارت سمجھنے
لگے گا اور اُسے بچانے کی کوشش کرنے کی بجائے الٹی یہ کوشش کرے گا کہ اگر ہو سکے تو
میں اسے اور بھی کسی طرح نقصان پہنچاؤں تو وہ ایک انسانیت سے گرا ہوا شخص سمجھا
جائے گا اور اس کی فطرت مُردہ قرار دی جائے گی.اسی طرح جو شخص اپنے مذہب کو نجات کا رستہ سمجھنے کی وجہ سے دوسروں سے
نفرت و حقارت کرتا ہے اور ان کو نقصان پہنچانے کے درپے رہتا ہے وہ ایک غیر فطری
فعل کا مرتکب ہوتا ہے.اور ایسے شخص کے متعلق کبھی بھی یہ نہیں سمجھا جا سکتا کہ وہ مذہب
کی حقیقت پر قائم ہے.اور اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ مذہب کی حقیقت کو نہیں
سمجھتے اور مذہب کی رُوح اُن کے اندر نہیں پائی جاتی وہی اس قسم کے خلاف فطرت
باتوں کے مرتکب ہوتے ہیں والا مذہب کی حقیقت کو سمجھنے والے لوگ غلط راستہ پر چلنے
والوں کے ساتھ ہمدردی کرتے اور ان کو گمراہی اور ہلاکت سے بچانے کی کوشش میں
رہتے ہیں اور نفرت و عداوت کا خیال تک بھی کبھی اُن کے دل میں نہیں آتا.علاوہ ازیں یہ نہیں سوچا گیا کہ مذہب کے انعامات اور افضال مادی مال کی طرح
نہیں ہیں کہ اُن کا وارث اس بات سے خائف ہو کہ اگر وہ کسی دوسرے کو مل گئے تو میں
اس سے محروم ہو جاؤنگا.بلکہ وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو دوسروں کو سکھانے سے ترقی
کرتی اور بڑھتی اور اسی لئے ایک مذہبی آدمی اس بات کی کوشش کرتا رہتا ہے کہ دوسرے
لوگ بھی اس کے مذہب کو قبول کر کے انعامات کے وارث بنیں.پس ایک غیر مذہب
185
Page 186
والے انسان سے اس وجہ سے نفرت کرنا بھی خارج از سوال ہے کہ وہ کہیں میرے
انعاموں میں کمی نہ کر دے.خلاصہ کلام یہ کہ کسی جہت سے بھی دیکھا جائے خدا کا عقیدہ یا مذہب کا تعلق
کسی صورت میں بھی تنگ خیالی اور فتنہ وفساد کا موجب نہیں ہوسکتا.اور اگر کوئی شخص
با وجود ایک مذہبی آدمی کہلانے اور خدا پر ایمان لانے کا دعویٰ رکھنے کے تنگ خیالی اور
مذہب کے نام پر فتنہ و فساد کا موجب ہوتا ہے اور بنی نوع انسان کے ساتھ
ہمدردی و محبت کے جذبات نہیں رکھتا بلکہ کینہ وعداوت کے خیالات رکھتا ہے اور تنگ دل
اور تنگ ظرف ہے تو وہ ہرگز ہرگز حقیقی معنوں میں مذہبی آدمی نہیں کہلاسکتا اور اس کا جسم
یقین مذہب کی مقدس روح سے اُسی طرح خالی ہے جس طرح ایک اجڑا ہو امکان مکین
سے خالی ہوتا ہے اور اس کا خُدا پر ایمان لانے کا دعویٰ صرف ایک زبانی دعوی ہے جس
کے اندر کچھ بھی حقیقت نہیں.مگر بدقسمتی سے اس قسم کے بے مایہ لوگ آجکل ہر ملت
میں کثرت کے ساتھ پائے جاتے ہیں اور اسلام بھی اس سے مستلخی نہیں.اور اسی وجہ
سے معترضین کو اعتراض کرنے کا موقعہ ملا ہے.مگر حقیقی طور پر مذہبی آدمی جو مذہب کی
حقیقت کو سمجھتا ہے بھی بھی تنگ ظرف اور فتنہ و فساد کا موجب نہیں ہو سکتا.یه درست.ست ہے کہ ایک حقیقی مومن باللہ کے ہاتھ سے بھی بعض اوقات دوسروں کو
تکلیف پہنچ جاتی ہے لیکن وہ تکلیف ایسی ہی ہوتی ہے جیسا کہ ایک مہربان ڈاکٹر اپنے
مریض کو ایک کڑوی دوا پینے یاکسی بظاہر تکلیف دہ پر ہیز کے اختیار کرنے پر مجبور کرتا
ہے.اور بے شک ایک رُوحانی آدمی بھی بعض اوقات دوسروں کے خلاف جنگ میں
حصہ لیتا اور بعض لوگوں کے قتل کئے جانے کا موجب ہو جاتا ہے، لیکن اس کا یہ فعل ایسا
ہی ہوتا ہے جیسا کہ ایک ہمدرد جراح کسی ایسے بیمار کا کوئی عضو کاٹ کر الگ کر دیتا ہے
جس کے متعلق وہ سمجھتا ہے کہ اگر اس کا یہ عضو کاٹ نہ دیا گیا تو اس کی جان ضائع
186
Page 187
ہو جائے گی.پس وہ ایک دردمند دل کے ساتھ زیادہ قیمتی چیز کے بچانے کے لئے کم
قیمتی چیز کوقربان کر دیتا ہے اور سب عقلمند لوگ اس کے اس فعل کو قابل تحسین خیال کرتے
ہیں.میرے عزیزو! میں تمہیں کس طرح یقین دلاؤں کہ خدا کے رسول اور پاک
بندے بھی جب کسی شخص یا گروہ کے خلاف ہاتھ اُٹھاتے ہیں تو اُن کے قلب صافی میں
بھی اس پاک نیت کے سوا اور کوئی خیال نہیں ہوتا اور اُن کا دل ایک لبریز چشمہ کی طرح
محبت و ہمدردی بنی نوع آدم کے جذبات سے ہر وقت معمور رہتا ہے.یہ ایک زندہ اور
ابدی حقیقت ہے جس کی تصدیق خدا کے پاک بندوں میں ہر زمانہ میں ملتی ہے.کاش تم
سمجھو!
ایک درمیانی عرض حال
اس مضمون کو آگے چلانے سے قبل میں ایک ضمنی عرض حال پیش کرنا چاہتا ہوں
اور وہ یہ ہے کہ میں نے یہ مضمون 1925 ء کے ماہ جون میں قادیان میں شروع کیا تھا
اور اس کا ابتدائی حصہ اسی موسم گرما میں منصوری میں تحریر کیا جہاں مجھے ڈاکٹری مشورہ
کے ماتحت جانا پڑا.اس کے بعد جب میں قادیان واپس آیا تو باقی حصہ 1925ء کے
اواخر میں اور کسی قدر 1926ء میں آہستہ آہستہ ضبط تحریر میں آیا اور اس کے بعد ایسے
حالات پیش آئے کہ یہ مضمون جس حد تک لکھا ہو اتھا اسی حد تک رہ کر آج کے دن تک
جو ابتدائے اکتوبر 1927ء ہے نامکمل پڑا رہا کیونکہ میرے نئے فرائض نے اس کی
طرف توجہ دینے کی فرصت نہیں دی.لیکن اب مجھے یہ خیال آیا اور نیز بعض دوستوں کی
طرف سے بھی یہ تحریک کی گئی ہے کہ جس حد تک بھی یہ مضمون لکھا جا چکا ہے اسے چھپوا
دینا چاہئے اور اس بات کا انتظار نہیں کرنا چاہئے کہ مضمون پوری طرح مکمل ہو تو تب
187
Page 188
شائع کیا جاوے.سومیں اس سوال کی بحث کو جو میں نے اس وقت شروع کیا ہوا ہے
اور جو خدا تعالیٰ کی ہستی کے متعلق عقلی دلائل سے تعلق رکھتا ہے مختصر طور پر چند صفحات میں
ختم کر کے مضمون کو سپر دطالع کرتا ہوں اور خدا سے دُعا کرتا ہوں کہ وہ اس مضمون کو
لوگوں کی ہدایت واصلاح کا موجب بنائے اور مجھے اس کے بقیہ حصص کی تکمیل کی توفیق
عطا کرے آمین.دراصل اس مضمون میں میرا ارادہ یہ تھا کہ خدا واند قدوس کی
ذات وصفات کے متعلق تمام سوالات کو مختصر طور پر زیر بحث لایا جائے.یعنی اس میں خدا
کی ہستی کے ہر دو قسم کے دلائل بھی ہوں جو عقلی استدلال اور مشاہدہ سے تعلق رکھتے
ہیں، اس کی صفات کی بحث بھی ہو، اس کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کے فوائد بھی تحریر کئے
جاویں ، اس کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کا طریق بھی بیان ہو اور یہ بھی بتایا جاوے کہ اس
کے تعلق کی کیا کیا علامات ہیں.مگر جیسا کہ ناظرین نے دیکھا ہے میں نے ابھی پہلے
سوال کا پہلا حصہ بھی جو خدا کی ذات کے متعلق عقلی دلائل سے تعلق رکھتا ہے ختم نہیں کیا.گویا پانچ سوالات میں سے ابھی تک نصف سوال بھی ختم نہیں ہو سکا اور زیادہ افسوس یہ
ہے کہ مضمون کا زیادہ اہم اور ضروری حصہ وہ ہے جو بقیہ مباحث سے تعلق رکھتا ہے.مگر
اب جو بھی ہے وہ ہدیہ ناظرین ہے اور بقیہ کے لئے خُدا سے دُعا ہے.وہ چاہے تو اسی کو
لوگوں کی ہدایت کا موجب بنادے.خُدا کا عقیدہ بدی کے ارتکاب سے روکتا ہے
دوسرا بڑا فائدہ جو خدا پر ایمان لانے کے نتیجہ میں دنیا کو عمومی طور پر حاصل ہو سکتا
ہے یہ ہے کہ خدا پر ایمان لانا انسان کو بدی کے ارتکاب سے روکتا ہے.ظاہر ہے کہ گناہ
اور مجرم سے باز رہنے کا خیال انسان کو امکانا تین طرح پیدا ہوسکتا ہے.اول یہ کہ انسان
کو یہ خیال ہو کہ اگر میں بدی سے باز رہا تو مجھے اس کے بدلے میں کوئی فائدہ پہنچے گا یا
188
Page 189
کوئی انعام حاصل ہوگا.دوسرے یہ کہ اگر میں گناہ کا مرتکب ہو اتو مجھے اس کے بدلے
میں کوئی تکلیف پہنچے گی یا کوئی سزا بھگتنی پڑے گی.اور تیسرے یہ کہ کسی شخص کا
علم و عرفان ہی ایسا ترقی کر جائے کہ وہ بدی سے محض اس وجہ سے اجتناب کرے کہ وہ
بدی ہے.ان تینوں روکوں کے علاوہ کوئی اور روک انسان کے لئے گناہ اور مجرم سے باز
رہنے کی نہیں ہے.اور ان تینوں میں سے بھی تیسری روک ایسی ہے کہ وہ خاص خاص
لوگوں کے ساتھ تعلق رکھتی ہے اور عامتہ الناس اس قسم کے خیال سے متاثر نہیں ہوتے.اور گواس تیسری روک سے فائدہ اُٹھانے میں بھی ایک مومن باللہ ایک غیر مومن پر یقیناً
فوقیت رکھتا ہے مگر باقی دوروکیں تو بالبداہت ایسی ہیں کہ خدا کا عقیدہ اُن میں بہت بڑا
دخل رکھتا ہے کیونکہ جو کوئی بھی خدا پر ایمان لاتا ہے وہ ساتھ ہی اس بات پر بھی یقین رکھتا
ہے کہ اگر میں نے بدی کا ارتکاب کیا تو خدا تعالے مجھ پر ناراض ہوگا اور اس ناراضگی
کے نتیجہ میں مجھے کوئی تکلیف پہنچے گی یا کوئی سزا بھگتنی پڑے گی اور اگر میں بدی سے
کنارہ کش رہا تو خدا مجھ پر خوش ہوگا اور اس کی خوشنودی میرے فائدہ کا موجب ہوگی
اور مجھے انعام و اکرام کا حقدار بنائے گی.پس اس خیال کے ماتحت ہر وہ شخص جو خدا پر
ایمان لاتا ہے اور اس کا ایمان محض دکھاوے کا ایمان نہیں وہ یقیناً دوسروں کی نسبت گناہ
سے زیادہ بچاہو اہوگا اور یہ ناممکن ہے کہ وہ خدا کا عقیدہ رکھتے ہوئے بدی کے ارتکاب
کی طرف جرات کے ساتھ قدم بڑھائے بلکہ جتنا جتنا کوئی شخص اپنے ایمان میں زیادہ
پختہ اور زیادہ کامل ہوگا اتنا ہی وہ گناہ اور جرائم سے زیادہ دُور اور زیادہ متنفر رہے گا.علاوہ ازیں خدا کا عقیدہ اس لحاظ سے بھی انسان کو بدی کے ارتکاب سے روکتا
ہے کہ ہر وہ شخص جو خدا پر ایمان لاتا ہے وہ ساتھ ہی خُدا کو حاضر وناظر اور عالم الغیب بھی
یقین کرتا ہے اور اس لئے اگر اس کا ایمان ذرا بھی حقیقت پر مبنی ہے اور محض دکھاوے یا
189
Page 190
ورثہ کا ایمان نہیں تو یقینا یہ خیال کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے اُسے بدی کے ارتکاب سے
باز رکھے گا.ظاہر ہے کہ ہر شخص کے ساتھ ہر وقت کوئی پولیس میں نہیں رہ سکتا اور اسی
لئے ملک کی سیاست خواہ وہ کتنی ہی اعلیٰ اور اکمل ہو جرائم کے ارتکاب کو رو کہنے میں کبھی
بھی پوری طرح کامیاب نہیں ہوسکتی.اور صرف ایمان باللہ ہی وہ چیز ہے جو ہر شخص کے
دل میں ہر وقت ایک ہوشیار و چوکس نگر ان کا کام دے سکتی ہے کیونکہ کوئی شخص خدا پر
ایمان لاتے ہوئے بشرطیکہ وہ ایمان کچھ حقیقت بھی اپنے اندر رکھتا ہو گناہ کی طرف
دلیری کے ساتھ قدم نہیں بڑھا سکتا.اور اگر کبھی کسی غفلت کی حالت میں ایسا شخص گناہ کا
مرتکب بھی ہوگا تو فوراً اس کا ایمان اُسے نادم کر کے آئندہ کے لئے ہوشیار کر دے گا.الغرض خدا کا عقیدہ ایک قطعی اور یقینی ذریعہ گناہ اور جرائم سے روکنے کا ہے اور کوئی عقلمند
انسان اس سے انکار نہیں کر سکتا.اور یہ ایک نہایت عظیم الشان فائدہ ہے جو اس عقیدہ
سے دنیا کو حاصل ہوسکتا ہے اور ہمیشہ ہوتا رہا ہے.اور اگر کوئی شخص یہ اعتراض کرے کہ خدا پر ایمان لانے والے بھی تو بدی کے
مرتکب ہو جاتے ہیں.تو اس کا جواب یہ ہے کہ بیشک خدا کا عقیدہ رکھنے والے لوگوں
میں سے بھی بعض لوگ بعض اوقات بدی کے مرتکب ہو جاتے ہیں لیکن اگر غور سے دیکھا
جائے تو یہ لوگ وہی ہوتے ہیں جو اپنے ایمان میں کمزور اور سست ہوتے ہیں یا جن کا
ایمان صرف نام کا ایمان ہوتا ہے جو انہوں نے ماں باپ سے ورثہ میں پایا ہوتا ہے اور
اس کے اندر زندگی کی رُوح نہیں ہوتی والا حقیقی طور پر ایمان لانے والے لوگ یقیناً
گناہوں سے بہت بچے ہوئے ہوتے ہیں.اور اگر کبھی وہ ٹھو کر کھاتے ہیں تو یہ ٹھو کر محض
عارضی ہوتی ہے جس کے بعد وہ فورا سنبھل کر ہوشیار ہو جاتے ہیں.اور یہ اس بات کا
ایک مزید ثبوت ہے کہ ایمان باللہ گناہ سے روکتا ہے ورنہ کوئی وجہ نہیں کہ پختہ ایمان
والے سُست ایمان والوں کی نسبت بدی سے زیادہ بچے ہوئے ہوں.بلکہ اگر
190
Page 191
دوسرے حالات برابر ہوں تو جتنا بھی کوئی شخص اپنے ایمان و عرفان میں ترقی یافتہ ہوگا
اتنا ہی وہ زیادہ گناہ سے پاک نظر آئے گا.الغرض یہ ایک بین حقیقت ہے جس سے
ہرگز انکار نہیں کیا جاسکتا اور جس کی صداقت پر ہر زمانہ میں مہر تصدیق لگتی چلی آئی ہے کہ
خدا پر ایمان لانا بشرطیکہ اس ایمان میں کچھ بھی حقیقت ہو دُنیا میں بدی کے سدِ باب کا
ایک بہت بڑا ذریعہ ہے.وهو المراد.یہ بحث بہت مفصل طور پر بیان کی جاسکتی
ہے لیکن اب چونکہ میں نے اس حصہ مضمون کو چند صفحات میں ختم کرنا ہے اس لئے اسی
مختصر بیان پر اکتفا کرتا ہوں.خُدا کا عقیدہ نیکی کی طرف رغبت پیدا کرتا ہے
تیسرا بڑا فائدہ جو ایمان باللہ سے دُنیا کو حاصل ہوسکتا ہے یہ ہے کہ خدا کا عقیدہ
نیکی کی طرف رغبت پیدا کرتا ہے اور اس بات کو اسی قسم کے دلائل سے ثابت کیا جاسکتا
ہے جو مندرجہ بالا بیان میں مختصر امذ کو ر ہوئے ہیں.اور میں نہیں سمجھ سکتا کہ کوئی عقلمند اس
سے انکار کر سکے لیکن اختصار کے خیال سے میں اس جگہ اس بحث کو صرف اسی قدر را شارہ
پر اکتفا کرتے ہوئے چھوڑتا ہوں.خُدا کا عقیدہ حقائق الاشیاء کی تحقیق میں محمد ہے
چوتھا بڑا فائدہ جو ایمان باللہ سے دنیا کو حاصل ہوتا ہے یہ ہے کہ خدا کا عقیدہ
حقائق الاشیاء کی تحقیق میں بہت ممد و معاون ہے.ظاہر ہے کہ جو شخص اس دُنیا کو بغیر کسی
خالق و مالک ہستی کے یقین کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ دُنیا محض کسی اتفاق کا نتیجہ ہے یا
یہ خیال کرتا ہے کہ کسی ابتدائی سادہ اور ادنیٰ حالت سے جس کے آغاز کے متعلق کچھ نہیں
191
Page 192
کہا جاسکتا یہ سارا کارخانہ عالم آہستہ آہستہ ارتقاء کے اندھے قانون کے ماتحت اپنی
موجودہ شکل وصورت کو پہنچا ہے وہ کبھی بھی حقائق الاشیاء اور قانون نیچر کی دریافت میں
اس شوق و ذوق اور امید کے ساتھ منہمک نہیں ہوسکتا جو اس معاملہ میں ایک مومن باللہ کو
حاصل ہو سکتے ہیں.خدا پر ایمان لانے والے شخص کا دل اس یقین و ایمان سے پُر ہوتا
ہے کہ دنیا کی ہر چیز میرے خدا کی پیدا کردہ ہے اور یہ کہ خدا نے ہر چیز کو ایک خاص
غرض و غایت کے ماتحت پیدا کیا ہے.اور اس لئے دنیا کی کوئی چیز بھی عبث اور باطل
نہیں بلکہ اپنی اپنی خلقت کی غرض وغایت کے ماتحت اپنے اپنے مفوضہ کام کو سرانجام
دے رہی ہے.اور ظاہر ہے کہ یہ یقین حقائق الاشیاء کی تحقیق کے معاملہ میں انسان کے
اندر ایک خاص ذوق و شوق اور اُمید در جا کی کیفیت پیدا کر دیتا ہے جو بغیر اس کے کبھی
بھی حاصل نہیں ہوسکتی.اور یہ کیفیت دُنیا کی علمی ترقی کے لئے ایک عظیم الشان
سہارے کا کام دیتی ہے.اس کے مقابل پر اگر ایک شخص خدا کا منکر ہے اور اس دنیا کو
محض اتفاق
کا نتیجہ قرار دیتا ہے تو وہ کبھی بھی حقائق الاشیاء کی دریافت میں اس شوق اور
اُمید کے ساتھ منہمک نہیں ہوسکتا کیونکہ وہ اپنے عقیدہ کے ماتحت اس بات کا امکان
تسلیم کرتا ہے کہ ایک چیز صرف کسی اتفاقی تغیر کانتیجہ ہو ا یونہی کی اندھے قانون کے چکر
میں آکر رونما ہو گئی ہو.اور اگر کبھی ایسا شخص علمی ترقی کے خیال سے کسی چیز کے حقائق کی
دریافت شروع بھی کرتا ہے تو پھر بھی وہ ہر گز اس استقلال و ہمت کے ساتھ اس کام کو
سرانجام نہیں دے سکتا جو ایک مومن باللہ کو میسر ہو سکتے ہیں.بلکہ اس کا دل ہر نا کامی پر
اس طرف مائل ہونے لگے گا کہ اب کسی مزید کوشش اور توجہ کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ یہ
خیال کرے گا کہ ممکن ہے کہ اس چیز میں کوئی خاص بات قابلِ دریافت ہو ہی نہیں.لیکن
خدا پر ایمان لانے والا شخص خواہ کتنی بھی ناکامیاں دیکھے وہ اس یقین سے کبھی بھی
متزلزل نہیں ہوگا کہ اس چیز میں ضرور کوئی خاص حکمت اور غرض وغایت ہے کیونکہ
192
Page 193
میرے خدا نے اسے یونہی عبث نہیں پیدا کیا.اور اس یقین کے نتیجہ میں وہ لازماً اپنی
ہر نا کامی کو اپنی کوشش کی کمی یا طریق تحقیق کی غلطی کی طرف منسوب کرے گا اور ہمت
نہیں ہارے گا.الغرض یہ ایک بین حقیقت ہے کہ خدا کا عقیدہ دنیا میں حقائق الاشیاء کی تحقیق
میں ایک نہایت مضبوط سہارے کا کام دیتا ہے اور اگر کوئی شخص یہ اعتراض کرے کہ ہم
عملاً دیکھتے ہیں کہ حقائق الاشیاء یعنی سائنس کے مختلف شعبوں کی تحقیق میں خدا کو ماننے
والے اور نہ ماننے والے سب ایک ہی طرح دلچسپی لیتے ہیں اور خدا کا عقیدہ اس معاملہ
میں ہرگز کوئی امتیاز نہیں پیدا کرتا بلکہ برخلاف اس کے اس قسم کے محققین زیادہ تر
یورپ و امریکہ میں پائے جاتے ہیں جہاں دہریت کے خیالات بلاد مشرقی کی نسبت
زیادہ رونما ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ خیال ایک سراسر دھو کے پر مبنی ہے کیونکہ
یورپ و امریکہ کے لوگ مذہبا د ہر یہ نہیں ہیں بلکہ خدا کو مانتے ہیں اور خواہ ان کا ایمان
کیسا ہی ناقص اور کمزور سمجھا جائے وہ بہر حال خدا کے منکرین میں سے نہیں سمجھے جاسکتے
اور یہ بات ان کے مسلمہ معتقدات میں داخل ہے کہ ہر چیز خدا کی پیدا کردہ ہے.پس
فی زمانہ حقائق الاشیاء کے علم میں ان
کا بڑھا ہو اہونا ہرگز موجب اعتراض نہیں ہوسکتا.باقی رہا یہ امر کہ ان میں دہریوں کی تعداد نسبتاً زیادہ ہے سو یہ بھی ایک خیال ہی خیال ہے
کیونکہ جب تک اعداد و شمار سامنے نہ ہوں اس کے متعلق کچھ نہیں کہا جا سکتا.بالکل ممکن
ہے کہ بلاد مشرقی میں مغرب کی نسبت دہر یہ خیال کے لوگ زیادہ ہوں.بہر حال جب
تک کوئی بات ثابت نہ ہو اس پر کسی دعوی کی بنیاد کیونکر رکھی جاسکتی ہے؟
علاوہ ازیں ہمیں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہئے کہ چونکہ مغرب کے لوگ ظاہری
علوم میں زیادہ ترقی یافتہ ہیں اس لئے اُن کے سارے خیالات خواہ وہ انفرادی ہوں یا
قومی دنیا کے سامنے آجاتے ہیں.لیکن اس کے مقابلہ میں مشرقی ممالک میں بوجہ تعلیم
193
Page 194
کی کمی کے لوگوں کے انفرادی خیالات دنیا کے سامنے بہت کم آتے ہیں.اور علم النفس
کے مسئلہ کے ماتحت یہ بھی ممکن ہے کہ بعض صورتوں میں مشرقی لوگ خود بھی اپنے
خیالات کو اچھی طرح نہ سمجھتے ہوں کیونکہ تعلیم کی کمی کی وجہ سے ان لوگوں میں ذہنی محاسبہ
کی عادت بہت کم ہے.پس بالکل ممکن ہے کہ باوجود دہریت کے خیالات سے متاثر
ہونے کے وہ اپنی اس حالت کو عملاً محسوس نہ کرتے ہوں.مگر یورپ وامریکہ میں یہ
بات نہیں کیونکہ وہاں تعلیم کی زیادتی کی وجہ سے ہر شخص ذہنی محاسبہ کی عادت رکھتا ہے
اور اس لئے اس کا ہر ذہنی تغیر اس کے سامنے آتا رہتا ہے.اندریں حالات یہ بات
ہرگز غیر ممکن نہیں کہ مغرب میں باوجود دہریوں کی تعداد تھوڑی ہونے کے وہ زیادہ نظر
آتے ہیں اور مشرق میں باوجود ان کی تعداد زیادہ ہونے کے وہ تھوڑے نظر آتے
ہوں.پس جب تک یہ ثابت نہ کیا جائے کہ یورپ و امریکہ میں دہریوں کی تعداد
مشرقی ممالک کی نسبت سے واقعی زیادہ ہے اس وقت تک صرف ایک عامیانہ اعتراض
کوئی حقیقت نہیں رکھتا.لیکن اگر یہ فرض بھی کر لیا جائے کہ مغرب میں دہریوں کی تعداد
نسبتاً زیادہ ہے تو پھر بھی کوئی جائے اعتراض نہیں کیونکہ ہر شخص جو یورپ و امریکہ کی
تاریخ کا ذرا بھی مطالعہ رکھتا ہے جانتا ہے کہ ان ممالک میں دہریت کے خیالات ان کی
علمی ترقی کے آغاز کے بعد پیدا ہوئے ہیں.پس اگر بلاد غربی میں دہریت کا اثر مشرق
کی نسبت واقعی زیادہ ہے تو زیادہ سے زیادہ یہ نتیجہ نکالا جاسکتاہے کہ علی ترقی دہریت کا
باعث ہوئی ہے نہ یہ کہ دہریت کے اثر نے علمی ترقی کی طرف میلان پیدا کیا ہے.یا یہ
کہ خدا کا انکار خدا پر ایمان لانے کی نسبت علمی ترقی کا زیادہ شوق پیدا کرتا ہے.پس
اعتراض بہر حال باطل ہوا.اور اگر اس جگہ کسی کو یہ خیال پیدا ہو کہ پھر علمی ترقی دہریت کا کیوں باعث ہوئی
ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم اس بات
کو تسلیم نہیں کرتے کہ علمی ترقی حقیقتادہریت کا
194
Page 195
باعث ہوئی ہے یا ہو سکتی ہے.بلکہ حق یہ ہے کہ اس معاملہ میں لوگوں کو ایک سخت دھو کہ لگا
ہے جس کی وجہ سے انہوں نے ایک سرا سر غلط نتیجہ نکال لیا ہے.بات یہ ہے کہ علمی ترقی
کے نتیجہ میں لازماً ایک بیداری پیدا ہوتی ہے اور وہ جمود جو جہالت کا نتیجہ ہوا کرتا ہے
زندگی کی حرکت سے بدلنا شروع ہو جاتا ہے.اس حرکت کے نتیجہ میں بعض لوگ جن کا
ذہنی نشو ونما صحیح طور پر ترقی یافتہ نہیں ہوتا یا جوگر دو پیش کے حالات سے متاثر ہوکر یا کسی
غلط نہی میں مبتلا ہو کر غلط رستہ پر چل پڑتے ہیں اُن کے واسطے یہی بیداری اور یہی زندگی
کی حرکت ٹھوکر کا موجب ہو جاتی ہے.مگر اس کے مقابلہ میں جہالت اور لاعلمی کی
تاریکیوں میں گھرے ہوئے لوگ چونکہ بوجہ اپنے جمود کے ایک ہی جگہ ٹھہرے رہتے
ہیں اس لئے ان کو غلط راستہ پر پڑنے کا کوئی موقعہ پیش ہی نہیں آتا.کسی شاعر نے خوب
کہا ہے کہ ؎
گرتے ہیں
شہسوار ہی میدان جنگ میں
وہ طفل کیا گرے گا جو گھٹنوں کے بل چلے
مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ شہسوار کی شہسواری اُسے گراتی ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ
چونکہ شہسوار کو گرنے کے مواقع پیش آتے رہتے ہیں اس لئے وہ کبھی کبھی گر بھی جاتا
ہے.پس اگر یورپ و امریکہ میں دہریت کا اثر زیادہ ہے تو اس کی سوائے اس بات کے
اور کوئی وجہ نہیں کہ علمی ترقی نے اُن کی جمود کی حالت کو زندگی کی حرکت سے بدل دیا
ہے.یعنی پہلے وہ خواب غفلت میں پڑے ہوئے ایک ہی جگہ ٹھہرے ہوئے تھے مگراب
ہوشیار ہو کر اُٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور چلنے پھرنے لگ گئے ہیں جس کے نتیجہ میں لازماً
وہ اگر ترقی کر رہے ہیں تو اُن میں سے بعض لوگ بھٹک بھی رہے ہیں.ٹھوکریں بھی
کھاتے ہیں.گرتے بھی ہیں.مگر ظاہر ہے کہ یہ علم کا قصور نہیں اور نہ علم اس کا باعث
ہے بلکہ یہ علم کے غلط استعمال کا جس میں بعض لوگ مبتلا ہو جایا کرتے ہیں ایک طبعی نتیجہ
195
Page 196
ہے.لیکن اس کے مقابل میں جو قوم مطلقا علم کا استعمال ہی نہیں کرتی وہ جیسا کہ صحیح
استعمال کی برکات سے محروم ہوتی ہے اسی طرح غلط استعمال کے بدنتائج سے بھی محفوظ
رہتی ہے اور یہی حال اس وقت یورپ و امریکہ کے مقابلہ میں بلا دمشرقی کا ہے.پس
بہر حال یورپ و امریکہ کی حالت کو ہمارے دعوی کی تردید میں پیش کرنا ہرگز درست
نہیں ہوسکتا.باقی رہا یہ سوال کہ دہریوں میں بھی حقائق الاشیاء کی تحقیق کا شوق رکھنے والے
کیوں پائے جاتے ہیں؟ سو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے ہرگز یہ دعوی نہیں کیا کہ اس قسم
کی علمی تحقیق کا شوق صرف خدا کے عقیدہ سے ہی پیدا ہوسکتا ہے اور دُنیا کی اور کوئی چیز
اس کا باعث نہیں ہوتی.بلکہ ہم تو اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ دنیا میں بہت سی چیزیں
اس قسم کا شوق اور میلان پیدا کرنے کا موجب ہوتی ہیں.پس اگر ایک دہر یہ دوسرے
موجبات سے متاثر ہو کر اس شوق میں لگ جائے تو ہر گز قابلِ اعتراض نہیں.ہمارا دعویٰ
تو صرف یہ ہے کہ خدا کا عقیدہ حقائق الاشیاء کی تحقیق میں خاص طور پر ممد و معاون ہوتا
ہے اور اگر دوسرے حالات برا بر ہوں تو ایک مومن باللہ یقیناً ایک کافر باللہ کی نسبت
حقائق الاشیاء کی دریافت میں زیادہ طبعی جوش رکھنے والا، زیادہ شائق، زیادہ پُر اُمید،
زیادہ مستقل مزاج اور زیادہ باہمت ثابت ہوگا کیونکہ وہ دُنیا کی ہر چیز کو ایک خاص
غرض و غایت کے ماتحت پیدا شدہ یقین کرتا ہے اور دہریہ کو یہ یقین حاصل نہیں.اور یہ
ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا.خُدا کا عقیدہ اطمینانِ قلب پیدا کرتا ہے
پانچواں بڑا فائدہ جو خدا کے عقیدہ سے دُنیا کو حاصل ہوسکتا ہے یہ ہے کہ خُدا پر
ایمان لانا انسان کے دل میں ایک گونہ اطمینان کی حالت پیدا کر دیتا ہے.اور یہ
196
Page 197
اطمینانِ قلب زندگی کے ہر شعبہ میں انسان کے کام آتا ہے.بلکہ حق یہ ہے کہ دنیا کا کوئی
کام بھی ایسا نہیں جو اطمینان قلب کے بغیر خیر و خوبی کے ساتھ سرانجام پاسکے.ایک
ہر یہ کا دل ہمیشہ بے اطمینانی اور بے چینی اور عدم یقین کے خیالات کا شکار رہتا ہے اور
اُسے بھی بھی اپنی حالت پر بشرطیکہ وہ ایک صاحب شعور اور مذہبی مذاق کا آدمی ہو
اطمینان نہیں ہوتا بلکہ ہر وقت اس کے دل میں ایک دُبدھا اور خلش لگی رہتی ہے کہ ممکن
ہے میری تحقیق غلط ہو اور ممکن ہے کہ میرے اوپر واقعی کوئی خالق و مالک موجود ہو.در اصل دہریت چونکہ محض ایک منفی علم ہے اور اس کی بنیاد کسی اثباتی دلائل پر قائم نہیں
یعنی عموماً ایک دہر یہ یہ نہیں کہتا اور نہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے یقیناً معلوم کر لیا ہے کہ کوئی
خُدا نہیں ہے.بلکہ وہ صرف اس حد تک رہتا ہے کہ میرے پاس خُدا کے موجود ہونے کا
کوئی ثبوت نہیں.اور نیز اس کی فطرت بھی اپنی گہرائیوں میں دہریت کو قبول نہیں کرتی
اس لئے اس کے دل میں اپنے اس عقیدہ کے متعلق یقین اور اطمینان کی حالت کبھی بھی
پیدا نہیں ہوتی اور اس کی فطرت اور نور عقل اور گردو پیش کے حالات اس کے دل
میں ایک بے چینی کی کیفیت پیدار کھتے ہیں.اور یہ بے چینی اسکی زندگی کو مضطرب اور
اس کے خیالات کو پریشان کر دیتی ہے اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دُنیا کے کسی کام میں بھی
یکسوئی اور اطمینان نہیں پاتا.اس کے مقابلہ میں خُدا کا عقیدہ چونکہ ایک زبردست اثباتی بنیاد پر قائم ہے اور
فطرتِ انسانی بھی اس میں اطمینان پاتی ہے اس لئے ایک مومن باللہ کو نسبتاً زیادہ
جمعیت خاطر اور یکسوئی حاصل رہتی ہے اور اس کے لئے کوئی حالتِ منتظرہ باقی نہیں رہتی
جو اسے پریشان رکھے اور وہ اپنے ہر کام میں اپنی حالت مطمئنہ سے فائدہ اُٹھاتا ہے.علاوہ ازیں ایک دہریہ کو یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ شاید کوئی خُدا ہو اور میں اس کا انکار
کر کے یونہی نقصان اُٹھاؤں اور یہ اندیشہ اس کے دل کو مضطرب رکھتا ہے.لیکن اگر
197
Page 198
بالفرض ایک مومن باللہ کو یہ خیال پیدا بھی ہو کہ شاید کوئی خدا نہ ہو تو پھر بھی اس کے اندر
کوئی اضطراب پیدا نہیں ہوسکتا کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اگر کوئی خدا نہ ہوا تو پھر بھی میرے
لئے کوئی خطرہ نہیں.الغرض جس طرح بھی دیکھا جائے خدا کا عقیدہ اطمینانِ قلب کا
موجب ہوتا ہے اور خدا کا انکار بے چینی اور پریشانی اور عدم یقین کا باعث.اور اسی
لئے قرآن شریف فرماتا ہے کہ:.الَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ
یعنی ”اے لوگو! اس بات کو خوب اچھی طرح سُن لو کہ دل کا اطمینان صرف خدا
کے تصور اور اس کے ذکر سے ہی حاصل ہو سکتا ہے.اور چونکہ انسان کے ہر کام میں اطمینان قلب کی ضرورت ہے اور دُنیا کا کوئی کام
بھی ایسا نہیں جو اس اطمینان کے بغیر کامل طور پر سرانجام پاسکے اس لئے ثابت ہوا کہ خدا
کا عقیدہ اس رنگ میں بھی دُنیا کی ترقی و بہبودی میں بہت بڑا دخل رکھتا ہے.خُدا کے عقیدہ سے اخلاق کا معیار قائم ہوتا ہے
چھٹا بڑا فائدہ جوخدا پر ایمان لانے کے نتیجہ میں دنیا کو حاصل ہوسکتا ہے میر ہے،
کہ خُدا کا عقیدہ دُنیا میں اخلاق کا معیار قائم کرنے کا موجب ہے جو اس کے بغیر بھی
بھی قائم نہیں ہوسکتا.علم الاخلاق جسے انگریزی میں ایتھکس (Ethics) کہتے ہیں اس
کے جاننے والے اس بات کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اخلاق کا کوئی معیار قائم کرنا
کس قدر مشکل کام ہے.بلکہ حق یہ ہے کہ اس فن کے ماہرین نے بڑی بڑی بحثیں کر
کے اور بڑی دماغ سوزی کے بعد جو تعریف نیکی کی کی ہے اور جو معیار اخلاق کا قائم کیا
ہے اس میں اس قدر اختلاف ہے کہ عقل حیران ہوتی ہے کوئی کچھ کہتا ہے اور کوئی کچھ.سورة الرعد - آیت 29
198
Page 199
اور سب ایک دوسرے پر اعتراض کرتے ہیں اور نتیجہ دیکھو تو کچھ بھی نہیں.لیکن اس کے
مقابلہ میں اگر ہم ایمان باللہ کے دائرہ میں داخل ہو کر غور کریں تو بات بالکل صاف
ہو جاتی ہے اور وہ یہ کہ انسان خود بخود اپنے آپ سے نہیں ہے کہ اس کے اخلاق کے
معیار کے لئے ہمیں اپنی طرف سے کسی سوچ بچار اور غور وفکر کی ضرورت ہو اور ہم اس
بات کی تلاش میں اپنی توجہ صرف کریں کہ اس کے لئے کونسا فعل اور کونسا طریق اچھا
سمجھا جانا چاہئے.بلکہ وہ ایک بالا ہستی کا پیدا کردہ ہے اور ظاہر ہے کہ اس صورت میں
انسان کے لئے اس بالا ہستی کے سوا اور کوئی نمونہ قابل تقلید نہیں ہوسکتا.اور اس کے
اخلاق کا معیار سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ اپنے آپ کو اپنے خالق و مالک کی صفات
کے رنگ میں رنگین کرے.چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ :.تَخَلَّقُوْا بِأَخْلَاقِ اللَّهِ
66
یعنی اے لوگو ! تم اپنے اخلاق کو خدا کے اخلاق کے مطابق بناؤ.“
اور اسی لئے اسلام یہ بھی تعلیم دیتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے انسان کو اپنی صفات کا ظلت
بنا کر پیدا کیا ہے اور جملہ صفات (سوائے ان صفات کے جو الوہیت کے لیے مخصوص
ہیں ) انسان کی فطرت کے اندر ایک چھوٹے اور محدود پیمانہ پر بطور ختم کے ودیعت کر دی
ہیں اور پھر ان فطری تخموں کی صحیح آب پاشی اور صحیح پرورش اور ترقی کے لئے اس نے اپنے
پاک بندوں کے ذریعہ اپنی طرف سے وقتاً فوقتاً ایک ضابطہ عمل نازل فرمایا ہے جسے
شریعت کہتے ہیں اور یہی وہ معیار اخلاق ہے جو دُنیا کی حقیقی اصلاح اور ترقی کا موجب
ہوسکتا ہے اور اس کے بغیر کوئی اور معیار تلاش کرنا اپنی محنت کو ضائع کرنا ہے.خوب سوچ لو کہ اخلاق کا کوئی صحیح معیار اس کے بغیر قائم نہیں کیا جاسکتا کہ انسان
اپنے خالق و مالک کی صفات و اخلاق کے ساتھ اپنے آپ کو متصف کرے.جس کی عملی
صورت یہ ہے کہ جو فطری جذبات انسان کے اندر پائے جاتے ہیں اور جو خود اپنی ذات
199
Page 200
میں خدا کی ہستی کی ایک دلیل ہیں کیونکہ وہ خدا کی صفات کا ظل ہیں انہیں مطابق احکام
شریعت
صحیح طریق پر استعمال کر کے خدا کے رنگ میں رنگین ہونے کی کوشش کی جائے.مثلاً محبت ایک فطری جذبہ ہے اور اس کا صحیح استعمال یعنی ایسا استعمال جو خدا کے رنگ
میں انسان کو رنگین کر دے ایک اعلیٰ خلق ہے، وفاداری ایک فطری جذبہ ہے اور اس کا
صحیح استعمال ایک اعلیٰ خلق ہے ، رحم ایک فطری جذبہ ہے اور اس کا صحیح استعمال ایک اعلیٰ
خلق ہے ، غضب ایک فطری جذبہ ہے اور اس کا صحیح استعمال ایک اعلیٰ خلق ہے، غیرت
ایک فطری جذبہ ہے اور اس کا صحیح استعمال ایک اعلیٰ خلق ہے، اور اسی طرح اور بہت
سے فطری جذبات ہیں جن کا صحیح استعمال ایک اعلیٰ خلق ہے.اور یہ سب جذبات
فطرت انسانی کے اندر خالق فطرت کی طرف سے اپنے خلق ہونے کی حیثیت سے
ودیعت کئے گئے ہیں اور جہاں تک انسان کا تعلق ہے یہ سب جذبات اپنی ذات میں نہ
اچھے ہیں اور نہ بُرے بلکہ محض سادہ فطری جذبات ہیں اور صرف ان
کا صحیح یا غلط استعمال
ان کو اچھا یا بر اخلق بناتا ہے اور اس صحیح اور غلط استعمال کا معیار یہ ہے کہ انسان کے ان
ا
فطری جذبات کا اظہار خدائی صفات کے رنگ میں ہو جس کے علم کا ذریعہ خدا کا فعل یعنی
نیچر اور خدا کا قول یعنی شریعت ہے اور اس کے سوا علم الاخلاق کی پیچیدہ گتھیوں کا اور
کوئی حل نہیں.اور یہ ایک عظیم الشان فائدہ ہے جو ایمان باللہ سے دُنیا کو حاصل ہوسکتا
ہے.اسی طرح اور بھی بہت سے فوائد ہیں لیکن اس جگہ صرف ان فوائد کے بیان پر ہی
میں اس بحث کو ختم کرتا ہوں.مگر میں یہ بات پھر بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہاں صرف ان
فوائد کی بحث تھی جو عمومی طور پر ایمان باللہ کے عقیدہ سے دُنیا کو حاصل ہو سکتے ہیں اور
ان عظیم الشان مخصوص فوائد کا ذکر نہیں جو ایک مومن باللہ قرب الہی میں ترقی کر کے
روحانی یا اخلاقی یا علمی طور پر حاصل کر سکتا ہے اور جو خدا کی مقرب جماعتوں کو حاصل ہوا
200
Page 201
کرتے ہیں اور ان کا بیان انشاء اللہ تعالیٰ اپنی جگہ پر کیا جائے گا.میں یہ بھی بتادینا چاہتا
ہوں کہ میں نے ان عمومی فوائد کا ذکر اس غرض سے نہیں کیا کہ یہ خدا کی ہستی کی دلیل نہیں
بلکہ جیسا کہ میں اوپر بیان کر چکا ہوں میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ اگر خدا واقعی
موجود نہیں ہے تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ چونکہ خدا کے ماننے سے کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے
اس لئے اسے یو نہی بلا دلیل مان لینا چاہئے بلکہ یہ بحث صرف ضمنی طور پر اس جگہ داخل
کی گئی ہے تا کہ یہ ثابت ہو کہ نہ صرف یہ کہ ہمارا ایک خالق و مالک واقعی موجود ہے بلکہ
یہ کہ اس پر ایمان لا نا دنیا کے لئے نفع بخش بھی ہے.دہریت کے دلائل کی مختصر تر دید
اب میں نہایت مختصر طور پر بعض ان دلائل کی تردید کرنی چاہتا ہوں جو د ہر یوں
کی طرف سے اپنے عقیدہ کی تائید میں پیش کئے جاتے ہیں.ان میں سے بہت سی
باتوں کا جواب تو اوپر کے مضمون میں آگیا ہے کیونکہ جہاں جہاں میں نے
ہستی باری تعالیٰ کی کوئی دلیل پیش کی ہے وہاں ساتھ ہی اس دلیل کے متعلق معترضین
کے عام اعتراضات کا جواب بھی تحریر کر دیا ہے.لیکن بعض باتیں ایسی ہیں جو کسی اثباتی
دلیل کی ضمن میں نہیں آسکتی تھیں اور اس لئے وہ اوپر کی بحث میں نہیں آئیں لہذا اس جگہ
صرف ان مؤخر الذکر باتوں کے متعلق بحث کی جائے گی اور باقی باتوں کے متعلق صرف
مختصراً اشارہ کر دیا جائے گا تا کہ مضمون کی تدوین مکمل رہے.تین قسم کی دہریت
سب سے پہلے یہ جانا چاہئے کہ دنیا میں وہر یہ خیال کے لوگ تین قسم کے پائے
201
Page 202
جاتے ہیں :.اوّل وہ دہر یہ جو صرف یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ خدا کا موجود ہونا ثابت نہیں ہے.یعنی چونکہ ہمارے پاس خدا کے موجود ہونے کی کوئی صحیح اور مضبوط دلیل نہیں ہے اس
لئے ہم اُسے نہیں مانتے اور انہی لوگوں کی کثرت ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ دہریوں میں
اس خیال کے لوگ شاید توے فیصدی سے بھی زیادہ ہونگے.دوسرے وہ دہر یہ جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہستی باری تعالیٰ کا مسئلہ ایک ایسا مسئلہ
ہے کہ وہ دلائل کے ساتھ ثابت ہو ہی نہیں سکتا یعنی یہ ممکن ہی نہیں کہ خدا کے موجود
ہونے یا نہ ہونے کے سوال کو دلائل کے ساتھ حل کیا جاسکے.ایسے لوگ بھی عملاً خدا کو
نہیں مانتے.تیسرے وہ دہر یہ جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ کوئی خدا موجود نہیں ہے.یعنی وہ یہ
خیال کرتے ہیں کہ خدا کا موجود نہ ہونا بعض دلائل وقرائن سے ثابت ہے.مگر ایسے
لوگ بھی اپنے عقیدہ کی حقیقی بنیاد ان دلائل پر نہیں رکھتے بلکہ ان کی حقیقی بنیاد بھی صرف
اس بات پر ہوتی ہے کہ خُدا کے موجود ہونے کا کوئی ثبوت نہیں لیکن ضمنی طور پر وہ بعض
دلائل بھی پیش کرتے ہیں.مگر یہ لوگ بہت ہی تھوڑے ہیں اور غالبا د ہریوں میں ان کی
تعداد ایک فیصدی سے زیادہ نہیں ہوگی بلکہ شاید اس سے بھی کم ہو.گویا پہلی قسم کے دہریوں کے عقیدہ کا خلاصہ ” عدم تسلیم بوجہ عدم ثبوت ہے.دوسری قسم کے دہریوں کے عقیدہ کا خلاصہ ” عدم تسلیم و انکار بوجه عدم امکان ثبوت و
انکار ہے اور تیسری قسم کے دہریوں کے عقیدہ کا خلاصہ انکار بوجہ وجوہ انکار ہے اور
جیسا کہ اوپر بیان کیا جاچکا ہے دہریوں میں پہلی قسم کے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے
اور تیسری قسم کے لوگوں کی تعداد بہت ہی کم ہے اور درمیانی قسم کے لوگوں کی تعداد بھی کم
ہے مگر تیسری قسم سے زیادہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ یورپ و امریکہ کے دہریوں نے
202
Page 203
جو نام اپنے لئے پسند کیا ہے وہ اگناسٹک (Agnostic) ہے جس کے معنے نہ جانے
والے کے ہیں.یعنی انہوں نے اپنی پوزیشن صرف یہ رکھی ہے کہ ہمارے پاس خدا کے
موجود ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ہے اور مثبت انکار کی پوزیشن کو ان لوگوں نے اختیار نہیں
کیا.الغرض دہریوں میں بہت زیادہ کثرت ان ہی لوگوں کی ہے جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں
کہ چونکہ خدا کے موجود ہونے کا کوئی ثبوت نہیں اس لئے ہم اس پر ایمان نہیں لاتے اور
بس.مگر اس جگہ ہمیں ان لوگوں کے عقائد کی تردید مقصود نہیں کیونکہ ان کے خیالات کی
تردید میں تو در حقیقت یہ سارا مضمون ہی بھرا پڑا ہے اور ہر اثباتی دلیل کے ضمن میں ایسے
لوگوں کے شبہات کا بھی ازالہ کیا جاتا رہا ہے اور دوسرے اثباتی دلائل جو اگلے
حصہ مضمون کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں وہ انشاء اللہ اپنے وقت اور موقعہ پر آگے چل کر
بیان کئے جائیں گے.اسی طرح دوسری قسم کے دہریوں کے عقائد کی تردید بھی اوپر کی
بحث میں خود بخود آگئی ہے اور باقی انشاء اللہ آگے آئے گی.پس اس جگہ میرا مقصد
صرف تیسری قسم کے لوگوں کے خیالات کی تردید ہے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بعض
دلائل اور قرائن سے خدا کا نہ ہونا ثابت ہے اور ان لوگوں کے عقائد کی تردید میں بھی
میں اس جگہ صرف ان باتوں کو بیان کرونگا جو گذشتہ مضمون میں کسی جگہ بیان نہیں ہوئیں
کیونکہ بعض جگہ اوپر کے مضمون میں ان لوگوں کے عقائد کی تردید بھی ضمناً بیان کی جاچکی
ہے اور اس جگہ اس کے اعادہ کی ضرورت نہیں صرف اشارہ کافی ہو گا.سو جاننا چاہئے کہ
اس قسم کے دہر یہ لوگ اپنے خیال کی تائید میں مندرجہ ذیل دلائل پیش کرتے ہیں :
دہریت کی پہلی دلیل اور اُس کا رڈ
پہلی دلیل جو یہ دہر یہ اپنے عقیدہ کی تائید میں پیش کرتے ہیں یہ ہے کہ اس
کائنات کے متعلق امکانا دوہی صورتیں ہو سکتی ہیں.ایک یہ کہ اسے کسی بالا ہستی نے پیدا
203
Page 204
کیا ہے.دوسرے یہ کہ وہ خود بخود اپنے کسی اندرونی قانون اور سلسلہ اسباب وعلل
کے ماتحت ہمیشہ سے یا کسی خاص زمانہ سے چلتی چلی آرہی ہے.ان دوصورتوں کے
علاوہ اور کوئی صورت عقلِ انسانی تجویز نہیں کرتی اور گو یہ دونوں صورتیں عقل انسانی کے
ادراک سے بالا ہیں.یعنی ہماری عقل اس بات کے سمجھنے سے قاصر ہے کہ ایک چیز
(خواہ وہ خدا ہو یا کائنات) خود بخود ہمیشہ سے یا کسی خاص زمانہ سے چلتی چلی آرہی ہے
لیکن ہم مجبور ہیں کہ انہی دوصورتوں میں سے کسی صورت
کو قبول کریں کیونکہ اس کے بغیر
کوئی تیسری صورت ممکن نہیں ہے.اور جب ہم نے انہی میں سے کسی ایک کو قبول کرنا
ہے تو دنیا کے متعلق یہ تسلیم کر لینا کہ وہ اپنے اندرونی سلسلہ اسباب و علل کے ماتحت خود
بخود چلتی چلی آرہی ہے زیادہ آسان اور زیادہ سادہ اور زیادہ محفوظ ہے بہ نسبت اس کے
کہ اس کائنات کے اوپر کسی بالا ہستی کو مان کر پھر اس کے متعلق یہی صورت تسلیم کی
جائے کہ وہ خود بخود ہمیشہ سے ہے وغیرہ وغیرہ.اس دلیل کا مفصل رڈ اوپر گذر چکا ہے (دیکھو کتاب ہذا صفحہ 91 تا 100)
جہاں کا ئنات عالم کی بناء پر ہستی باری تعالیٰ کے متعلق اثباتی دلیل بیان کی گئی.ا ہے اور
اس جگہ اس کے اعادہ کی ضرورت نہیں.وہاں پوری تشریح کے ساتھ یہ ثابت کیا گیا تھا
کہ یہ کارخانہ عالم اور ذات باری تعالیٰ اپنے حالات وصفات کے اختلاف کی وجہ سے
ایک حکم میں نہیں آسکتے اور نہ یہ سمجھا جاسکتا ہے کہ دونوں کو ہمیشہ سے خود بخود مانا ایک ہی
رنگ رکھتا ہے.بلکہ حق یہ ہے کہ جہاں خدا اپنے صفاتِ الوہیت کی وجہ سے اس بات کو
چاہتا ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہو اور اس کے اوپر کوئی بالا ہستی نہ ہو وہاں یہ دنیا ومافیہا اپنے
حالات سے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ وہ خود بخود ہمیشہ سے نہیں ہیں اور نہ اس بات میں
کوئی امر مانع ہے کہ ان کے اوپر کوئی اور بالا ہستی موجود ہو.پس فرق ظاہر ہے اور اس
↓
اس ایڈیشن کے صفحات 87 تا 102 (پبلشرز )
204
Page 205
لئے دونوں کو ایک قیاس کے ماتحت ہرگز نہیں لایا جاسکتا اور یہ بالکل غلط ہے کہ دنیا کو
ہمیشہ سے مانا نسبتاً زیادہ آسان اور زیادہ سادہ اور محفوظ ہے بلکہ دنیا کو ہمیشہ سے ماننے
میں اس قدر اشکال پیش آتے ہیں کہ جن کا کوئی حل نہیں ہوسکتا.ہاں البتہ دُنیا کو مخلوق
مان کر اُس کے خالق کو ہمیشہ سے مانا یقیناً زیادہ قریب الفہم اور زیادہ قرین قیاس اور
زیادہ سادہ اور زیادہ محفوظ امر ہے اور پھر خدا کے موجود ہونے کے دلائل مزید براں
ہیں.اگر ضرورت ہو تو ناظرین اس بحث کو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں جو اس امر کے متعلق
او پر گذر چکی ہے اس جگہ اعادہ کی ضرورت نہیں.دہریت کی دوسری دلیل اور اُس کا رڈ
دوسری دلیل ہستی باری تعالیٰ کے انکار کی ان دہریوں کی طرف سے یہ پیش کی
جاتی ہے کہ قانون نیچر اور سلسلہ اسباب و علل اس قدر کامل و کمل ہے کہ اس کے ہوتے
ہوئے اس کائنات کے لئے قطعاً کسی خدا یا کسی بالا ہستی کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی.اور بغیر کسی ضرورت کے کسی بالا ہستی کو مانا ایک وہم سے زیادہ حقیقت نہیں رکھتا وغیرہ
وغیرہ.اس دلیل کارڈ بھی اوپر گذر چکا ہے (دیکھو کتاب ہذا صفحہ 68 تا 77) جہاں یہ
بتایا گیا تھا کہ کس طرح با وجود ایک مکمل قانون کے ایک بالا ہستی کی ضرورت باقی رہتی
ہے اور نیز یہ بھی بتایا گیا تھا کہ باوجود اس سلسلۂ اسباب و علل کے اس دُنیا میں ایک
خاص غرض و غایت اور ایک خاص منشاء حیات کا پایا جانا ایک صانع ومتصرف ہستی پر
دلالت کر رہا ہے.ضرورت ہو تو اس بحث کو بھی اوپر دیکھا جاسکتا ہے.اعادہ کر کے
مضمون کو طول دینے کی ضرورت نہیں.دراصل یہ نہیں سوچا گیا کہ گو اسباب و علل اپنی
ذات میں بھی ایک صانع اور نگران ہستی کو چاہتے ہیں لیکن اگر ایسانہ بھی سمجھا جائے تو پھر
اس ایڈیشن کے صفحات 62 تا 79 (پبلشرز )
205
Page 206
بھی وہ ایسے اوزار کی حیثیت تو بہر حال ضرور رکھتے ہیں جن سے ایک کاریگر آگے ایک
چیز تیار کرتا ہے جو ان اوزار کے استعمال کا نتیجہ ہوتی ہے اور کاریگر کا وجود زیادہ تر اسی
نتیجہ سے ظاہر ہوا کرتا ہے.پس یہ اسباب و علل خدا کی ہستی کے خلاف ہرگز بطور دلیل
کے پیش نہیں کئے جاسکتے بلکہ حق یہ ہے کہ ان اسباب کا وجود اور پھر اس سے بھی بڑھ کر
یہ کہ ان اسباب کا نتیجہ جو اس کائنات کے ایک خاص سمت میں اور ایک خاص
غرض و غایت کے ماتحت چلنے سے ظاہر ہورہا ہے ایک بالا ہستی کے موجود ہونے کا بتین
ثبوت ہے جس سے کوئی عقلمند انکار نہیں کرسکتا.دہریت کی تیسری دلیل اور اُسکا رڈ
تیسری دلیل جو بعض دہریوں کی طرف سے پیش کی جاتی ہے اور جس سے وہ
خُدا کی ہستی کے خلاف استدلال کرتے ہیں وہ مسئلہ ارتقاء پر مبنی ہے اور اس کا خلاصہ یہ
ہے کہ ارتقاء کی پیش کردہ تھیوری نے یہ بات ظاہر کر دی ہے کہ جو چیزیں اس وقت دنیا
میں نظر آتی ہیں ان کی موجودہ شکل وصورت ہمیشہ سے ایسی نہیں تھی کہ جواب ہے بلکہ
ابتداء میں وہ ایک ادنیٰ حالت میں تھیں اور پھر آہستہ آہستہ ارتقاء کر کے اپنی موجودہ
شکل وصورت کو پہنچی ہیں.یعنی ہر چیز آہستہ آہستہ اپنے ماحول کے مناسب حال صورت
اختیار کرتی گئی ہے اور جو چیزیں اس ماحول کے مطابق تغیر پذیر نہیں ہو سکیں وہ آہستہ
آہستہ ضائع ہو گئیں.اور اس سے یہ لوگ استدلال کرتے ہیں کہ اس عالم میں کوئی
ترتیب (Design or Plan) نہیں ہے بلکہ موجودہ کا ئنات محض اتفاقی حالات کا
اس دلیل کا اصولی رڈ بھی اوپر گذر چکا ہے.(دیکھو کتاب ہذا صفحہ 76 تا85)
اس ایڈیشن کے صفحات 71 تا 87 (پبلشرز )
206
Page 207
علاوہ ازیں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہئے کہ ماحول کے مناسب حال نہ ہونے کی وجہ سے
بعض چیزوں کا ضائع ہو جانا اور بعض کا اپنے آپ
کو آہستہ آہستہ ماحول کے مطابق بنالینا
ہرگز اس بات کو ثابت نہیں کرتا کہ دُنیا بغیر کسی ترتیب (Design or Plan) کے
ہے.بلکہ اگر نظر غور سے دیکھا جائے تو یہی بات کہ بعض چیزیں ضائع ہو جاتی ہیں اور
بعض قائم رہتی ہیں عالم میں ایک ترتیب اور ایک علت غائی اور ایک منشاء حیات کو
ثابت کر رہی ہے.کیونکہ بعض چیزوں کا گر جانا اور بعض کا قائم رہنا سراسر حکمت کے
فعل کا نتیجہ ہے اور اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ خالق کا ئنات اپنے باغ کی بہبودی و ترقی
کے خیال سے درختوں کی کانٹ چھانٹ کرتا رہتا ہے اور جو شاخیں یا جو پودہ جات کمزور
ہوتے ہیں اور کسی نقص کی وجہ سے تغیرات زمانہ کے اثرات کو برداشت نہیں کر سکتے اور
اپنی پیدائش کی غرض کو پورا کرنے سے قاصر رہتے ہیں انہیں کاٹ کر گرا تا جاتا ہے تا کہ
دوسرے مناسب حال پودے جو ترقی کی طاقت رکھتے ہوں زیادہ آزادی کے ساتھ
نشو و نما پائیں اور ان کمز ور شاخوں یا پودوں کا وجود اُن کی ترقی میں روک نہ ہو
اور اگر یہ کہا جائے کہ جب خدا کو یہ علم تھا کہ باغ کائنات کی فلاں فلاں شاخ یا
پودا کمزور رہے گا اور اپنی پیدائش کی غرض کو پورا نہیں کر سکے گا تو اُس نے اُسے پیدا ہی
کیوں کیا ؟ تو اس کا یہ جواب ہے کہ خدا نے تو تمام چیزوں کو ایک خاص غرض وغایت
کے ماتحت پیدا کیا ہے اور اس کا یہی منشا ہے کہ وہ اس غرض و غایت کو پورا کریں.لیکن
اگر کوئی چیز عام قانونِ نیچر کے ماتحت اپنے اندر کوئی نقص پیدا کرلتی ہے اور زندگی کے
میدان میں دوسری چیزوں کے ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی اور اپنی خلقت کی غرض کو پورا
کرنے سے قاصر رہتی ہے تو قانون نیچر کے ماتحت ہی وہ گر جاتی ہے.گویا کہ دونوں
قانون خدا ہی کے بنائے ہوئے ہیں یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو ایک خاص غرض و غایت
کے ماتحت پیدا کرتا ہے اور اس کا منشاء یہ ہوتا ہے کہ وہ اس غرض و غایت کو پورا کرے
ہو.207
Page 208
اور یہ بھی کہ جو چیز ضرر رساں اثرات کے ماتحت آکر اس غرض و غایت کے پورا کرنے
سے قاصر رہے وہ ضائع ہو جائے.جس طرح مثلاً ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے رُوحانی اور
مادی ترقی کے لئے پیدا کیا ہے لیکن بعض انسان اپنے اعمال کی وجہ سے اس غرض کو پورا
نہیں کرتے اور پھر وہ بوسیدہ شاخوں کی طرح کاٹ دیئے جاتے ہیں.دوسرے یہ بھی یا درکھنا چاہئے کہ جو چیزیں ضائع ہو جاتی ہیں بعض صورتوں میں
قانون نیچر کے ماتحت اُن کی پیدائش کی غرض ہی یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک عرصہ تک قائم رہ
کر دوسری چیزوں کی ترقی میں امداد دیں اور پھر جب یہ دوسری قائم رہنے والی چیزیں
مستحکم ہو جائیں اور اپنے اس کمال کو پہنچ جائیں جو ان کی پیدائش کا مقصد ہے تو ان
سہارا دینے والی چیزوں کو ضائع کر دیا جائے.جیسا کہ زراعت میں بھی بعض اوقات
بعض پودہ جات لگائے جاتے ہیں اور بعض دوسرے پودہ جات جن کا وجود بالذات
مقصود نہیں ہوتا اور جنہیں انگریزی میں فلرز (Fillers) کہتے ہیں ان پودہ جات کی
حفاظت اور پرورش اور ترقی کے لیے اُن کے آس پاس لگا دئے جاتے ہیں اور پھر جب
اصل پودہ جات اچھی طرح مستحکم ہو جاتے ہیں تو یہ زائد پودے ضائع کر دیئے جاتے
ہیں کیونکہ اب ان کی پیدائش کی غرض پوری ہو چکی ہوتی ہے اور اس کے بعد ان کا قائم
رہنا ان پودہ جات کے لئے جو بالذات مقصود ہیں ضررساں ہوتا ہے.علاوہ ازیں سائنس سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ بعض چیزوں کا مرنا ہی اپنی
ذات میں دوسری چیزوں کی زندگی اور استحکام اور ترقی کا موجب ہوتا ہے اور اس لئے
ان کی پیدائش کی غرض ہی یہ ہوتی ہے کہ وہ خود مرکر دوسروں کی زندگی اور ترقی کا باعث
بنیں.اور اس کی بیشمار مثالیں دی جاسکتی ہیں.الغرض کسی طرح بھی دیکھا جائے بعض چیزوں کا ایک وقت تک چل کر ضائع
ہو جانا اور بعض کا قائم رہنا اور ترقی کر جانا ہرگز خدا کی ہستی کے خلاف بطور دلیل کے
208
Page 209
پیش نہیں کیا جاسکتا.بلکہ اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس دُنیا کے اوپر ایک مدرک
بالا رادہ حکیم و علیم ہستی موجود ہے جو ایسے حکیمانہ طور پر ایک خاص غرض و غایت کے
ماتحت دنیا کے کارخانہ کو چلا رہی ہے.باقی رہا یہ سوال کہ جو چیزیں ضائع ہوتی ہیں وہ محض اس قانون کے نتیجہ میں
ضائع ہوتی ہیں کہ کمزور چیز گر جاتی ہے اور مضبوط باقی رہتی ہے اور اس میں کسی بالا ہستی
کا ہاتھ تلاش کرنا ایک وہم سے بڑھ کر نہیں.تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم ہر گز قانون کے
منکر نہیں بلکہ ہم تو خود اس سلسلۂ اسباب و علل کے قائل اور اس کے پیش کرنے والے
ہیں مگر اس قانون اور سلسلہ اسباب و علل سے یہ بات ہر گز ثابت نہیں ہو سکتی کہ اس کے
اوپر کوئی خُدا نہیں ہے.بلکہ جیسا کہ اوپر مفصل بیان کیا جاچکا ہے کہ خود اس
سلسلہ اسباب و علل کا وجود ایک بالا ہستی کی طرف اشارہ کر رہا ہے اور ان اسباب کا
مجموعی نتیجہ ایک زائد روشن دلیل ہے.اس جگہ میں پھر دوبارہ یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ
مسئلہ ارتقاء جس صورت میں کہ ڈارون وغیرہ نے پیش کیا ہے ہرگز سائنس کی کوئی ثابت
شدہ حقیقت نہیں بلکہ صرف ایک تھیوری ہے جس کی بعض تفصیلات سے بہت سے
دوسرے سائنسدان اتفاق نہیں کرتے بلکہ اب تو یہ تھیوری اپنی موجودہ صورت میں
بالکل رڈ ہی کی جاچکی ہے.دہریت کی چوتھی دلیل اور اس کا رڈ
چوتھی دلیل جو دہریوں کی طرف سے ہستی باری تعالیٰ کے خلاف پیش کی جاتی
ہے وہ بھی مسئلہ ارتقاء پر مبنی ہے.یعنی کہا جاتا ہے خلق عالم اور خلق آدم کے متعلق جو
تعلیم مذاہب نے پیش کی ہے وہ سب مسئلہ ارتقاء کی روشنی میں غلط اور باطل ثابت ہوگئی
ہے اور اس لئے یہ معلوم ہوا کہ مذاہب کی تعلیم جُھوٹی اور خلاف واقعہ ہے اور جب
209
Page 210
مذاہب باطل ہو گئے تو خدا کا عقیدہ بھی جو انسان کو مذہب سے حاصل ہوا ہے خود بخود
باطل اور غلط ثابت ہو گیا.اس دلیل کے متعلق بھی اوپر کے مضمون میں مفصل بحث گذر
ما ہے ( دیکھو کتاب ہذا صفحہ 85 تا 93) اور اس اعتراض کا کافی وشافی جواب دیا
جاچکا ہے اور اب اس جگہ اس کے اعادہ کی ضرورت نہیں.دہریت کی پانچوں دلیل اور اُس کا رڈ
یا
پانچویں دلیل جو دہریوں کی طرف سے پیش کی جاتی ہے یہ ہے کہ جس
قانون نیچر کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ ایک بالا ہستی کا پیدا کردہ ہے وہ بعض صورتوں اور
بعض حالات میں ایسا ظالمانہ ہے اور اس طرح اندھا دھند طریق پر چلتا ہے کہ کوئی شخص
اس کا مطالعہ کر کے اس نتیجہ پر نہیں پہنچ سکتا کہ یہ کسی صاحب شعور نہستی کا پیدا کردہ ہے
بلکہ اس کے مطالعہ سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ یونہی کسی اندرونی تغیر
سلسلہ اسباب و علل کے نتیجہ میں یہ سب کچھ چل رہا ہے.مثلا بعض اوقات غیر معمولی
حادثات کا پیش آنا اور اُس کے نتیجہ میں بے گناہ لوگوں کا نقصان اُٹھانا یا مارا جانا.وباؤں اور بیماریوں کا پھیلنا.مصائب و آلام کا پیش آنا.بعض بچوں کا اندھایا بہرہ یاکولا
یا مجنون پیدا ہونا کسی شخص یا چیز کا شاہراہ ترقی پر چلتے چلتے تباہی و بربادی کی طرف مائل
ہوجانا وغیرہ وغیرہ.یہ سب باتیں جو آئے دن دُنیا میں ہوتی رہتی ہیں اس بات کا ثبوت
ہیں کہ دُنیا کے اوپر کوئی خدا و غیرہ نہیں ہے ورنہ یہ اندھیر نگری اور یہ مصائب و آلام ہرگز
نہ ہوتے.یہ اعتراض ایک ایسا اعتراض ہے جس کا جواب اوپر کے مضمون میں نہیں آیا.الہذا ضروری ہے کہ کسی قدر تفصیل کے ساتھ اس کا جواب لکھا جائے.اس ایڈیشن کے صفحات 88 تا 96 (پبلشرز )
210
Page 211
قانون نیچر اور قانون شریعت میں امتیاز کرنا ضروری ہے
سو جاننا چاہئے کہ یہ اعتراض صرف اس وجہ سے پیدا ہو ا ہے کہ معترضین نے ان
دو قسم کے قوانین پر پوری طرح غور نہیں کیا جو خدا کی طرف سے اس دُنیا میں جاری ہیں
اور یہی سمجھ رکھا ہے کہ دُنیا کا سارا کاروبار ایک ہی قانون کے ماتحت چل رہا ہے.حالانکہ یہ بالکل غلط ہے اور حق یہ ہے کہ خُدا کی طرف سے دُنیا میں دو مختلف قانون
جاری ہیں.ایک قانون نیچر ہے جو نظامِ عالم کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور سلسلہ
اسباب و علل اور خواص الاشیاء کے ماتحت جاری ہے اور جس کے اثرات و نتائج اسی دُنیا
میں ساتھ ساتھ رونما ہوتے جاتے ہیں.دوسرا قانونِ شریعت ہے جو انسان کے
اخلاق وروحانیات کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور انبیاء و مرسلین کے ذریعہ دنیا میں نازل
ہوتا رہا ہے اور جس کی جزا سزا کے لئے بعد الموت کا وقت مقرر ہے اور مندرجہ بالا
اعتراض ان دو قانونوں کے مخلوط کر دینے اور ان کے صحیح امتیاز کو لوظ نہ رکھنے کے نتیجہ میں
پیدا ہوا ہے.قانونِ نیچر کیا ہے؟ قانونِ نیچر یہ ہے کہ دُنیا کی ہر چیز اور ہر بات اور ہر حرکت
اور ہر سکون اور ہر مفرد اور ہر مرکب میں ایک معین فطری تاثیر رکھی گئی ہے جو اس کے
طبعی نتیجہ کے طور پر ظاہر ہوتی رہتی ہے.مثلاً یہ بات قانون نیچر کا حصہ ہے کہ سنکھیا میں
جاندار چیز کے مار دینے کی خاصیت ہے اور جب بھی اور جہاں بھی سنکھیا کسی جاندار چیز
کے اندر اس مقدار میں جائے گا جو اسے مار دینے کے لئے کافی ہے تو اُس کا طبعی نتیجہ
رونما ہو گا سوائے اس کے کہ قانون نیچر کا ہی کوئی دوسرا قانون جو اس کے اثر کے مٹانے
کے لئے مقرر ہے دخل انداز ہو کر اس کے اثر کو مٹا دے.اسی طرح یہ بات قانونِ نیچر کا
حصہ ہے کہ اگر کوئی چھت کمزور اور بودی ہوگی تو کسی ایسے وقت جب کہ اس کی کمزوری
اس حد کو پہنچ جائے کہ وہ قائم نہ رہ سکے وہ گر جائے گی.اور یہ بات بھی اسی قانونِ نیچر کا
211
Page 212
حصہ ہے کہ گرنے والی چھت کے نیچے اگر کوئی شخص آئے گا تو وہ مر جائے گا.پس جو
شخص بھی اس قانون کی زد میں آئے گا وہ یقیناً ہلاک ہو گا سوائے اس کے کہ اس قانون
کے اثر کو مٹادینے والا کوئی اور قانون درمیان میں دخل انداز ہو جائے.اسی طرح یہ
بات قانون
نیچر کا حصہ ہے کہ جو شخص غرقاب پانی کے اندر جاتا ہے اور وہ تیر نانہیں جانتا
وہ ڈوب جائے گا.پس جو شخص بھی تیرنا نہ جاننے والا گہرے پانی میں داخل ہوگا وہ
موت سے بچ نہیں سکے گا سوائے اس کے کہ کوئی اور قانون جو اس کے اثر کو مٹا دینے کی
خاصیت رکھتا ہوا سے بچالے.اسی طرح یہ بات قانون نیچر کا حصہ ہے کہ خواہ کوئی چیز
کتنی ہی ترقی یافتہ ہو اس کے رستے میں جب کوئی ضرر رساں اور نقصان دہ چیز میں حائل
ہونگی اور اس کو اُن کے مقابلہ کی طاقت نہیں ہوگی تو اُس کی ترقی رک کر تنزل و انحطاط کی
صورت پیدا ہو جائے گی سوائے اس کے کہ قانون نیچر ہی کے ماتحت ان موانع کے اثر کو
مٹادینے والے ذرائع میسر آجائیں.یہ سب باتیں اور اسی قسم کی لا تعداد دوسری باتیں
قانون نیچر کا حصہ ہیں اور اس قانون کے ماتحت ہر چیز اپنے طبعی اثرات پیدا کر رہی ہے
اور اس عظیم الشان مشین کے پہیئے ہر وقت حرکت میں ہیں اور ان کے لئے اپنے اور
بیگانے کا کوئی سوال نہیں ہے بلکہ عام حالات میں (یعنی مستثنیات کو الگ رکھ کر جن کے
لئے ایک الگ مستقل اُصول ہے جو خدا کی تقدیر خاص سے تعلق رکھتے ہیں اور عموماً
انبیاء و اولیاء کے ذریعہ دُعاؤں کی قبولیت اور معجزات وغیرہ کی صورت میں ظاہر ہوتے
ہیں) جو بھی اُن کے سامنے آجائے اُسے وہ اپنے مقررہ فرائض کے ماتحت اوپر کی
طرف اُٹھانے یا نیچے کی طرف گھرانے.آگے کی طرف بڑھانے یا پیچھے کی طرف ہٹانے
میں مجبور ہیں.برخلاف اس کے قانونِ شریعت کیا ہے؟ قانون شریعت وہ قانون اور وہ
ضابطہ عمل ہے جو کوئی مذہب اپنے متبعین کے سامنے خدا کی طرف سے پیش کرتا ہے
212
Page 213
تا کہ وہ اس پر عمل پیرا ہو کر اپنے اخلاق کو درست کریں اور خُدا کا قرب حاصل کر کے
ان فیوض و برکات سے حصہ پاویں جو خُدا کے پاک بندوں کے لئے مقدر ہیں.مگر اس
قانون کے ماتحت ہر شخص کو اختیار ہوتا ہے کہ چاہے تو اس قانون کی پابندی اختیار کرے
اور چاہے تو نہ کرے اور اس کی جزا سزا کے لئے موت کے بعد کا وقت مقرر ہے
(سوائے بعض خاص خاص نیم مخفی اثرات کے جو اسی دُنیا میں رونما ہو جاتے ہیں ) مثلاً
قانونِ شریعت انسان کو کہتا ہے کہ خدا کا قرب اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لئے
تمہیں چاہئے کہ اپنے خدا کی اس اس طرح عبادت
کرو.مگر وہ انسان کو اس عبادت پر
مجبور نہیں کرتا.یعنی اگر کوئی شخص اس ہدایت کے خلاف چلنا چاہے تو وہ خلاف ورزی
کر سکتا ہے اور کوئی چیز اس
کا ہاتھ نہیں روکتی اور گو اس خلاف ورزی کا اثر بار یک طور پر
اسی دُنیا میں ظاہر ہو جائے مگر اس کی اصل اور معتین سزا اگلے جہان میں ہی ملتی ہے اور
اسی لئے مذہبی لوگوں میں یہ ایک عام مقولہ ہے کہ دنیا دارالعمل ہے اور اگلا جہان
دار الجزاء ہے.مگر قانون نیچر کی یہ حالت نہیں بلکہ اس کے لئے یہی دنیا دارالعمل ہے اور یہی
دار الجزاء ہے.اور یہ دونوں قانون سوائے استثنائی حالات کے جن کے بیان کی اس
جگہ ضرورت نہیں ہے بھی ایک دوسرے کے دائرہ عمل میں دخل انداز نہیں ہوتے.یعنی
ایسا نہیں ہوتا کہ اگر کوئی شخص نیچر کے کسی قانون کی زد میں آجائے تو پھر وہ اس کے اثر
سے صرف اس وجہ سے محفوظ رہے کہ وہ قانون شریعت کے لحاظ سے مجرم نہیں ہے بلکہ
عام حالات میں وہ یقیناً قانون نیچر کی زد میں آنے کا نتیجہ بھگتے گا.اور قانون شریعت کی
پابندی اُسے اس نقصان اور تکلیف سے نہیں بچا سکے گی.مثلاً اگر ایک چھت بوجہ
کمزوری کے گرنے والی ہو اور اس کے نیچے دو شخص بیٹھے ہوں جن میں سے ایک مذہب
کے لحاظ سے بہت اچھا آدمی ہو اور دوسرا بد کردار اور عاصی ہو تو عام حالات میں ایسا
213
Page 214
نہیں ہوگا کہ چھت کے گرنے کے وقت اچھا آدمی بچ جائے اور بدکردار مر جائے.بلکہ
اگر چھت ایسے طور پر گرے گی کہ اس کے نیچے آنے والے بیچ نہ سکیں تو دونوں مریں
گے اور اگر قانون نیچر کے ماتحت بیچنے کی کوئی صورت ہوگی تو دونوں بچ جائیں گے اسی
طرح اگر کوئی نیک اور متقی آدمی غرقاب پانی میں داخل ہو جاتا ہے اور وہ تیرنا نہیں جانتا
تو اس کی نیکی اُسے ڈوبنے سے نہیں بچا سکے گی کیونکہ اس کی نیکی قانون شریعت کے
دائرہ سے تعلق رکھتی ہے مگر یہاں قانون نیچر کا دائرہ عمل ہے جسے عام حالات میں
قانونِ شریعت کی کوئی پاسداری ملحوظ نہیں.خلاصہ کلام یہ کہ قاعدہ یہی ہے کہ قانونِ شریعت کے دائرہ کی نیکی یا بدی صرف
شرعی جزا سزا میں اثر رکھتی ہے اور قانون نیچر کی جزا سزا کے وقت اس کا کوئی وزن
نہیں.اور اسی طرح قانون نیچر کی اطاعت یا نافرمانی صرف نیچر کے جزا سزا میں اثر
رکھتی ہے اور قانونِ شریعت کی جزاء سزا کے وقت اس کا کوئی وزن نہیں.پس ایک
دہریہ کا اپنے عقیدہ کی تائید میں یہ کہنا بالکل فضول اور باطل ہے کہ مثلاً فلاں شخص جو بڑا
نیک اور شریف آدمی تھا اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے وہ دریا پر نہانے گیا اور
اچانک ڈوب کر مر گیا.حالانکہ اُسی وقت ایک آوارہ مزاج آدمی بھی دریا پر نہا رہا تھا
مگر وہ صحیح سلامت گھر واپس آ گیا.یا فلاں لڑکی جو نہایت پاکباز اور خوش اخلاق تھی وہ
اپنی شادی کے دوسرے دن ہی آگ لگ جانے سے ہلاک ہوگئی.حالانکہ ایک دوسری
لڑکی جو سخت بد اخلاق اور بدچلن تھی اور اس کی شادی بھی اسی دن ہوئی تھی مزے سے
زندگی گزار رہی ہے.یا فلاں بچہ جو نہایت بھولا بھالا اور نیک سیرت تھا چھت کے نیچے
دب جانے سے مر گیا حالانکہ اسی وقت اس کے قریب ایک شریر اور گندہ لڑکا بھی کھیل رہا
تھا جو چھت کے گرنے سے تھوڑی دیر پہلے کمرہ سے نکل گیا تھا اور اس پر کوئی مصیبت
نہیں آئی وغیرہ وغیرہ.پس ایسی مثالیں دیکر کہا جاتا ہے کہ ثابت ہوا کہ ہمارے اوپر کوئی
214
Page 215
خدا نہیں ورنہ یہ اندھیر نگری اور یہ ظلم نہ ہوتا.خوب سوچ لو کہ یہ اعتراض بالکل بودا اور کمزور ہے کیونکہ جو شخص ڈوب گیا وہ گو
قانون مذہب کا پابند تھا مگر قانون
نیچر کا وہ مجرم بھی تھا.اور اس لئے اس نے نیچر کے
قانون کے ماتحت سزا پائی اور دوسرا آدمی باوجود قانون مذہب کا مجرم ہونے کے
قانون نیچر کی سزا سے بچ گیا.کیونکہ اس نے قانون نیچر کا کوئی جرم نہیں کیا تھا.اسی
طرح جو لڑکی جل کر مرگئی وہ قانون نیچر کی زد میں آگئی تھی اسی لئے وہ ہلاک ہوگئی اور
چونکہ یہ جزا سزا قانون
نیچر کی تھی اس لئے قانونِ شریعت کا پابند ہونا اُسے بچانہیں سکا
مگر دوسری لڑکی باوجود قانونِ شریعت کی مجرم ہونے کے قانون نیچر کی سزا سے بچی رہی
کیونکہ اس نے قانون
نیچر کا کوئی جرم نہیں کیا تھا.وعلیٰ ھذا القیاس.پس یہ کوئی اندھیر نگری نہیں اور نہ کوئی ظلم و ستم ہے بلکہ یہ تو نیچر کی سیاست کا ایک
طبعی نتیجہ ہے جوسب کے لئے برابر ہے.اندھیر تو تب ہوتا کہ نیچر کا کوئی قانون نہ ٹوٹتا
اور پھر بھی نیچر سزا دیتی یا یہ کہ قانون ٹوٹتا شریعت کا مگر سزا نیچر دیتی.یا یہ کہ قانون ٹوٹتا
نیچر کا اور سزا شریعت دیتی.مگر ایسا نہیں ہوتا بلکہ جو ہوتا ہے وہ صرف یہ ہے کہ نیچر کا
قانون ٹوٹتا ہے تو نیچر سزا دیتی ہے اور شریعت کا قانون ٹوٹتا ہے تو شریعت سزا دیتی
ہے.(سوائے مستثنیات کے جن کی بحث ایک الگ مستقل مضمون ہے اور اس جگہ اس
کے ذکر کی ضرورت نہیں ) اور کوئی عظمند اس بات کو موجب اعتراض یا خلاف انصاف
نہیں سمجھ سکتا.میں تو حیران ہوتا ہوں کہ معترضین کس عقل و دانش کے مالک بنکر اعتراض کی
طرف قدم بڑھاتے ہیں اور اس کارروائی کو جو سراسر حکمت پر مبنی ہے اور جس میں کوئی
قانون نہیں ٹوٹتا اور نہ دو مختلف قانون آپس میں ٹکراتے ہیں انصاف کے خلاف سمجھتے
ہیں.دراصل بد قسمتی سے سارا دھوکا یہ لگا ہے کہ واقعہ تو قانون نیچر کے ماتحت پیش آتا
215
Page 216
ہے اور اس کی وجہ قانونِ شریعت میں تلاش کی جاتی ہے اور وجہ کے نہ ملنے پر یہ خیال
کرلیا جاتا ہے کہ بس سب اندھیر نگری ہے.اے بدقسمت لوگو! خدا تمہیں عقل دے.نیچر کے واقعہ کی وجہ قانون نیچر میں تلاش کرو اور شریعت کی سزاؤں کی وجہ
قانون شریعت میں.تب تمہیں معلوم ہوگا کہ اندھیر نگری وہ نہیں جو ہورہا ہے بلکہ وہ ہے
جو تم کہتے ہو کیونکہ اس سے بڑھ کر اور کیا اندھیر نگری ہوگی کہ اگر کوئی شخص قانون نیچر کی
زد میں آجانے کی وجہ سے پانی میں ڈوب جائے یا آگ میں جل جائے یا چھت کے
نیچے دب کر مر جائے یا کسی اور طرح ہلاک ہو جائے تو تم یہ خیال کرنے لگ جاتے ہو کہ
چونکہ اُس نے قانونِ شریعت کے ماتحت کوئی گناہ نہیں کیا تھا اس لئے اس کے ساتھ ظلم
ہوا ہے.افسوس ! افسوس! ظالم تو تم ہو کہ قانون نیچر کا حق قانونِ شریعت کو دیتے ہو اور
قانون شریعت کا قانون نیچر کو اور پھر اعتراض کرتے ہو خُدا پر.خوب یاد رکھو کہ نیچر اور شریعت دو الگ الگ حکومتیں ہیں اور یہ حکومتیں مہذب
سلطنتوں کی طرح ایک دوسرے کے نظام میں دخل نہیں دیتیں.سوائے اس کے کہ خدا
کی مرکزی حکومت کسی اشد ضرورت کے وقت ایک ملک کی فوج کو دوسرے ملک کی
امداد کے لئے جانے کا حکم دے.جیسا کہ انبیاء و مرسلین کی بعثت کے وقت جبکہ دنیا کی
اصلاح کے لئے آسمان پر ایک خاص جوش ہوتا ہے بعض صورتوں میں قانون نیچر کی
طاقتوں کو قانونِ شریعت کی خدمت میں لگا دیا جاتا ہے چنانچہ معجزات و خوارق اسی
استثنائی قانون کی قدرت نمائی کا کرشمہ ہوتے ہیں.مگر عام قاعدہ یہی ہے کہ قانون نیچر
اور قانونِ شریعت بالکل الگ الگ رہتے ہیں اور ایک دوسرے کے دائرہ میں دخل نہیں
دیتے اور نہ ایک دوسرے کی خاطر اپنا رستہ چھوڑتے ہیں.الغرض یہ سارا دھو کہ ان
دونوں قانونوں کے مخلوط کر دینے اور ان کے امتیاز کوملحوظ نہ رکھنے کے نتیجہ میں پیدا ہوا
ہے ورنہ بات بالکل صاف اور واضح تھی.216
Page 217
تناسخ کا عقیدہ کس طرح پیدا ہوا ہے؟
اس جگہ یہ ذکر بھی خالی از فائدہ نہ ہوگا کہ تناسخ Transmigration of)
Soul یعنی اواگون کا عقیدہ بھی اسی غلطی پر مبنی ہے.کیونکہ تناسخ کے ماننے والے بھی
یہی دلیل دیتے ہیں کہ چونکہ جو بچے دُنیا میں پیدا ہوتے ہیں وہ مختلف حالات کے
ماتحت پیدا ہوتے ہیں یعنی کوئی بچہ تندرست پیدا ہوتا ہے تو کوئی کمزور ونحیف.کوئی
آنکھوں والا پیدا ہوتا ہے تو کوئی نا بینا.کوئی ہاتھ پاؤں والا پیدا ہوتا ہے تو کوئی ٹو لالنگڑا،
کوئی اچھے دماغ والا پیدا ہوتا ہے تو کوئی گند ذہن، کوئی امیر کے گھر پیدا ہوتا ہے تو کوئی
غریب کے، وغیر ذالک.اس سے ثابت ہوا کہ موجودہ زندگی سے پہلے کوئی اور زندگی
بھی گذر چکی ہے جس کے اعمال کی پاداش میں بچوں کی حالت مختلف ہوگئی ہے والا اگر
موجودہ زندگی سے پہلے کوئی زندگی نہیں گذری اور ان بچوں کے گذشتہ اعمال کا کوئی اچھا
یا بُرا ریکارڈ پہلے موجود نہیں ہے تو یہ اختلاف کیوں ہے؟ کیا خُدا ظالم ہے کہ اس نے
ایک ہی نسل کے بچوں کو اسقدر مختلف صورتوں اور مختلف حالات کے ساتھ پیدا کیا ہے؟
اور اگر خُدا ظالم نہیں ہے تو اس اختلاف کا حل سوائے اس کے اور کوئی نہیں ہوسکتا کہ اس
بات
کو تسلیم کیا جائے کہ ہماری موجودہ زندگی سے پہلے بھی کوئی زندگی گذر چکی ہے اور
پیدائش کے وقت کا اختلاف اسی گذشتہ زندگی کے اعمال کا نتیجہ ہے.یہ وہ دلیل ہے جو تناسخ یعنی اواگون کے ماننے والوں کی طرف سے پیش کی جاتی
ہے اور اس سے ظاہر ہے کہ ان لوگوں نے بھی قانونِ شریعت اور قانون نیچر کے امتیاز کو
کھلا کر ایک ہی قانون سے سارے واقعات کو ناپنا چاہا ہے اور یہ نہیں سوچا کہ پیدائش
کے وقت کا اختلاف قانونِ شریعت کے ماتحت نہیں ہے کہ اس کے لئے گذشتہ اعمال کا
ریکارڈ تلاش کیا جائے.بلکہ وہ قانون نیچر کے ماتحت ہے یعنی والدین بلکہ والدین سے
بھی اوپر کے اجداد کی جسمانی اور اقتصادی اور اخلاقی حالت سے بچہ حصہ پاتا ہے اور
217
Page 218
چونکہ مختلف بچوں کے والدین کے حالات مختلف ہوتے ہیں اس لئے بچوں کے حالات
بھی مختلف ہو جاتے ہیں.علم طب نے جو قانون
نیچر کا حصہ ہے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ اگر والدین
تندرست ہونگے تو بچہ بھی تندرست ہوگا اور اگر والدین کمزور ہو نگے تو بچہ بھی کمزور
ہو گا.حتی کہ بعض اوقات والدین کی جسمانی حالت کی تفصیلات میں بھی بچہ ان کا
وارث ہوتا ہے.یہ علم اس قدر وسیع ہے اور ایسے طور پر بار بار کے تجربات اور مشاہدات
سے پایہ ثبوت
کو پہنچ چکا ہے کہ کوئی عقلمند اس کا انکار نہیں کر سکتا.حتی کہ یہاں تک ثابت
ہو چکا ہے کہ جس وقت مرد اور عورت مخصوص تعلق کی غرض سے اکٹھے ہوتے ہیں تو اُن کی
اُس وقت کی حالت بھی پیدا ہونے والے بچہ پر ایک گہرا اثر پیدا کرتی ہے اور اسی لئے
شریعت اسلامی نے کمال حکمت سے اس بات کا حکم دیا ہے کہ جب مرد اور عورت اکٹھے
ہونے لگیں تو انہیں چاہئے کہ اپنے دل کے خیالات کو پاک وصاف بنالیں تا کہ بچہ اُن
کی اس ذہنی نیکی سے حصہ پائے.الغرض یہ بات علم طب کی رُو سے قطعی طور پر ثابت
ہو چکی ہے کہ والدین بلکہ والدین سے بھی اوپر کے اجداد کا اثر بچہ میں پہنچتا ہے اور یہ جو
دُنیا میں کوئی بچہ تندرست اور کوئی کمزور ، کوئی سیح وسلامت اور کوئی ناقص پیدا ہوتا ہے یہ
سب اسی اثر کا نتیجہ ہے.دراصل نیچر کا یہ ایک عام قانون ہے اور قرآن شریف نے بھی اس کی طرف
اشارہ کیا ہے جہاں فرمایا ہے کہ ہر چیز اپنے دائیں بائیں اثر ڈالتی ہے (سورۃ الفل.آیت 49) کہ دنیا کی چیزیں ایک دوسرے کے سہارے پر کھڑی ہیں اور ہر چیز ہر دوسری
چیز سے علی قدر مراتب اثر لے رہی ہے اور اپنا اثر اسے دے رہی ہے اور اسی اثر کے
ماتحت بچہ اپنے ماں باپ کی (جن سے وہ اقرب ترین تعلق رکھتا ہے ) اچھی یا بُری
حالت سے حصہ پاتا ہے.پس بعض لوگوں نے جو یہ سمجھ رکھا ہے کہ بچوں
کا پیدائش کے
218
Page 219
وقت کا اختلاف ان کی کسی پہلی جون کے اعمال کی وجہ سے ہے یہ بالکل غلط اور باطل
ہے اور اس غلطی کی وجہ یہی ہے کہ ایسے لوگوں نے قانونِ نیچر کے واقعات کی وجہ
قانون شریعت میں تلاش کرنی چاہی ہے.الغرض دہریوں اور تناسخ کے ماننے والوں کا عقیدہ دراصل ایک ہی غلطی پر مبنی
ہے یعنی دونوں نے قانون نیچر اور قانون شریعت کے امتیاز کو ملحوظ نہیں رکھا اور دونوں
نے نیچر کے واقعہ کی وجہ قانونِ شریعت میں تلاش کرنی چاہی ہے اور چونکہ ان کو ایسی
کوئی وجہ نظر نہیں آئی اس لئے اس پریشانی میں ان میں سے ایک گروہ تو اس طرف مائل
ہو گیا کہ نعوذ باللہ یہ سب اندھیر نگری ہے اور خدا و غیرہ کا خیال ایک خیال باطل ہے اور
دوسرا گروہ اس طرف مائل ہو گیا کہ چونکہ خدا ہے اور ظالم نہیں ہے کہ بلاوجہ کسی کو سزا
دے اس لئے بچوں کا پیدائش کے وقت کا اختلاف ضرور کسی پہلی جون کی وجہ سے ہوگا
اور اس طرح انہوں نے تناسخ یعنی اواگون کا عقیدہ قائم کر لیا.حالانکہ اگر یہ دونوں گروہ
ذرا غور سے کام لیتے تو بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے تھے کہ خدا کی طرف سے دُنیا میں
دومخلتف قانون جاری ہیں اور ان دونوں کا دائرہ عمل بالکل الگ الگ ہے اور یہ ایک
سخت غلطی ہے کہ قانون نیچر کے کسی واقعہ کی وجہ قانون شریعت میں تلاش کی جائے.خلاصہ کلام یہ کہ دنیا میں جو حادثات پیش آتے ہیں یا بیماریاں پڑتی ہیں یا مصائب
کا سامنا ہوتا ہے اور ان میں بعض اوقات نیک اور معصوم لوگ بھی نقصان اُٹھاتے ہیں
اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ قانونِ نیچر قانونِ شریعت سے الگ ہے اور قانونِ شریعت کی
نیکی قانون نیچر کی سزاؤں سے بچا نہیں سکتی جب تک ان احتیاطوں کو کام میں نہ لایا جائے
جو قانون نیچر خود اس کے لئے پیش کرتا ہے.مثلاً پانی میں ڈوبنا ایک نیچر کا واقعہ ہے اور
کسی شخص کی مذہبی نیکی اسے اس کے اثر سے بچا نہیں سکتی جب تک کہ کوئی شخص تیرنانہ
سیکھے یا بعض دوسری احتیاطوں
کو کام میں نہ لائے جو پانی کی غرقابی سے بچنے کے لئے نیچر
219
Page 220
پیش کرتی ہے.اسی طرح کسی بچے کا کمزور پیدا ہونا ایک نیچر کا واقعہ ہے اور اس کے لئے
کوئی شرعی وجہ تلاش کرنا فضول ہے بلکہ اس کے علاج کے لئے قانون
نیچر ہی کی طرف
رجوع کرنا چاہئے اور والدین کو اپنی بیماری کا علاج یا اپنی کمزوری کا ازالہ یا اپنے نقص کی
تلافی یا اپنے ماحول کی درستی کی طرف مائل ہونا چاہئے.انسانی ترقی کیلئے قانون نیچر کا قانون شریعت سے جدا اور آزاد رہنا
ضروری ہے.اگر کوئی شخص یہ اعتراض کرے کہ قانون نیچر کیوں قانونِ شریعت کا احترام نہیں
کرتا یعنی ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ جب ایک شخص نیکی اور تقویٰ اختیار کرتا ہے تو وہ
حادثات قضاء و قدر سے بھی محفوظ ہو جائے تو اس کا پہلا جواب تو یہی ہے کہ ایسا اس لئے
نہیں ہوتا کہ دونوں قانون مختلف ہیں اور دونوں کا الگ الگ کام ہے لیکن جو صورت
معترض نے تجویز کی ہے اس سے دونوں قانون ایک ہو جاتے ہیں اور الگ الگ قانون
کا وجود قائم نہیں رہتا حالانکہ دو الگ الگ قانونوں
کا پایا جانا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ
دونوں قانونوں کا الگ الگ وجود مقصود ہے.دوسرا اور حقیقی جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دو قانون انسان کی دو قسم کی
ترقیوں کے لئے جاری فرمائے ہیں.یعنی قانون نیچر انسان کی مادی ترقی کے لئے بنایا
گیا ہے اور قانونِ شریعت اس کی اخلاقی اور روحانی ترقی کے لئے ہے اور خدا کا منشاء یہ
ہے کہ انسان ہر جہت سے ترقی کرے.ایسی صورت میں اگر ایسا ہو کہ کوئی شخص محض
قانونِ شریعت کی پابندی اختیار کرنے کی وجہ سے قانونِ نیچر کا جرم کرتے ہوئے بھی
اس کے بداثرات سے بچ جائے تو یقیناً نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان کی مادی ترقی کا دروازہ
220
Page 221
بالکل مسدود ہو جائے گا.مثلاً اگر انسان کو اس کا نیک ہونا پانی کی غرقابی یا آگ کی
سوزش یا بجلی کی تباہی سے بچالے تو انسان کو کیا ضرورت ہے کہ وہ ان چیزوں کے خواص
کا مطالعہ کر کے ان کی ماہیت کو سمجھنے اور ان
کو قابو میں لانے کی کوشش کرے.خوب سوچ لو کہ انسان کی تمام مادی ترقی صرف اس اصل کی وجہ سے ممکن
ہو رہی ہے کہ وہ جب تک قانون نیچر کا مطالعہ کر کے اپنے لئے آرام اور بہبودی اور ترقی
کے دروازے نہیں کھولتا اُس کو آرام اور بہبودی اور ترقی میسر نہیں آتے اور اسی لئے وہ
ہر وقت نیچر کے مطالعہ اور خواص الاشیاء کی دریافت میں لگا رہتا ہے.انگریزی میں
ایک مثل ہے کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے.جس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان کسی
ضرورت سے مجبور ہو جاتا ہے تو تبھی وہ نئی چیزوں کی ایجاد کی طرف توجہ کرتا ہے.پس
اگر انسان کی مادی ضروریات محض قانونِ شریعت کی پابندی کی وجہ سے پوری ہو جایا
کریں تو یقیناً نتیجہ یہ ہو کہ انسان کی مادی ترقی بالکل رُک جائے اور دنیوی علوم کے تمام
دروازے اس پر بند ہو جائیں کیونکہ اس صورت میں کوئی شخص مادی امور کی دریافت اور
حقائق الاشیاء کی تحقیق میں وقت اور توجہ صرف نہیں کر سکتا.پس ان دونوں قوانین کا
ایک دوسرے کے کام میں دخل انداز نہ ہونا خدا کی طرف سے ایک عین رحمت کا فعل
ہے.اور یہ حادثات و غیرہ بھی اسی رحمت کا پیش خیمہ ہیں کیونکہ اگر دنیا میں کسی ایک فرد
پر کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو اس حادثہ کے نتیجہ میں جو بیداری اور اس قسم کے حادثات سے
بچنے کا علاج دریافت کرنے کی طرف جو توجہ پیدا ہوتی ہے وہ آئندہ کے لئے لاکھوں
کروڑوں انسانوں کو فائدہ پہنچا جاتی ہے اور ایک جان یا دس ہیں جانوں کے ضائع
جانے سے لاکھوں کروڑوں انسانوں کی جانیں آئندہ پیش آنے والے خطرات سے
محفوظ ہو جاتی ہیں.Necessity is the mother of invention
221
Page 222
الغرض یہ دونوں قانون انسان کی الگ الگ قسم کی ترقی کے لئے مقصود ہیں اور
ان کا مخلوط ہو جانا یا ایک دوسرے کی خاطر اپنے رستے سے ہٹ جانا بجائے فائدہ مند
ہونے کے یقیناً نہایت نقصان دہ اور نسل انسانی کی ترقی کے لئے از حد مہلک ہے.اور
حق یہی ہے کہ جو کچھ بھی اس وقت ان دو قانونوں کے ماتحت دُنیا میں ہو رہا ہے وہ
بنی نوع آدم کی مجموعی بہبودی اور ترقی کوملحوظ رکھتے ہوئے عین مناسب اور نہایت درجہ
حکیمانہ ہے اور اس سے بہتر کوئی صورت ذہن میں نہیں آسکتی.اس جگہ یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ جو نیک اور متقی لوگ حادثات کے نتیجہ میں یا کسی اور
طرح قانون نیچر کی زد میں آکر بظاہر بے وقت موت کا شکار ہو جاتے ہیں اور انکے لواحقین
کو بھی اُن کی اس رنگ کی موت سے غیر معمولی صدمہ یا نقصان پہنچتا ہے اُن کے لئے
اسلامی تعلیم سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ اُن کے واسطے اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل سے بعض
دوسرے ذرائع رحمت کے پیدا کر دیتا ہے کیونکہ اگر خدا ایک طرف دُنیا کی بہبودی اور ترقی
کے خیال سے اپنے قانون کا احترام کرواتا ہے اور عام حالات میں اس کو کسی فرد کی
غیر متعلق نیکی کی وجہ سے توڑتا نہیں تو دوسری طرف وہ اپنے نیک بندوں کے لئے ازحد
مہربان بھی ہے اور اپنے تعلق میں سب وفاداروں سے بڑھ کر وفادار ہے اس لیے وہ ضرور
ایسے موقع پر کسی اور ذریعہ سے ان کے نقصان کی تلافی کر دیتا ہے.مثلاً دنیوی مصیبت کی
وجہ سے آخرت میں ان کو خاص انعام و اکرام کا وارث بنادیتا ہے یا ان کے پسماندگان کو دنیا
کی برکات سے حصہ وافر دیدتا ہے یا اور کوئی ایسا طریق اختیار کرتا ہے جسے وہ اپنے رحم اور
انصاف کے مطابق مناسب سمجھے اور جس سے کسی دوسرے کا حق بھی ضائع نہ ہو.اسی طرح جو بچے قانون نیچر کی وجہ سے کمزور اور ناقص پیدا ہوتے ہیں اور ان کی
یه خلقی کمزوری یا نقص ان کی رُوحانی ترقی میں روک ہو جاتا ہے تو اس کے متعلق بھی
اسلام کی یہی تعلیم ہے کہ شرعی جزا سزا کے وقت خدا تعالیٰ ان کی اس معذوری کو ضرور ملحوظ
222
Page 223
رکھے گا اور ان نقصوں کی وجہ سے جن کا ازالہ ان کی طاقت سے باہر تھا ان پر مواخذہ
نہیں کرے گا اور نہ ان کے اعمال کی جزا کو ان کی کسی خلقی کمزوری کی وجہ سے کم ہونے
دے گا.کیونکہ جیسا کہ خُداقرآن میں فرماتا ہے اُس کا تر از وحق وانصاف کا ترازو ہے
اور کوئی چیز جو کسی نہ کسی جہت سے ذرا بھی وزن رکھتی ہے اس کے تول سے باہر نہیں رہ
سکتی اور نہ ہی اس کا قانون کسی قسم کے موجبات رعایت کو نظر انداز کرتا ہے.دُنیا میں گناہ کا وجود کیوں پایا جاتا ہے؟
اس جگہ ایک اور مشبہ کا ازالہ بھی ضروری ہے اور وہ یہ کہ دنیا میں گناہ اور ظلم و تعدی
کا وجود کیوں پایا جاتا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی خُدا ہوتا تو لوگ ہرگز اس طرح
گناہ و معاصم اور ظلم و ستم میں مبتلا نہ ہوتے اور بدی کا وجود دنیا میں نہ پایا جاتا.اس کا
جواب یہ ہے کہ معترضین نے قانونِ شریعت کی حقیقت اور غرض و غایت اور حکمت کو نہیں
سمجھا.قانونِ شریعت اس اصل پر مبنی ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے ایک ضابطہ عمل پیش
کر کے ان کو سمجھا دیتا ہے کہ تمہارے لئے اس ضابطہ پر کار بند ہونا ضروری ہے اور
تمہاری اخلاقی اور روحانی ترقی اس کے بغیر ممکن نہیں.لیکن اس سمجھا دینے کے بعد وہ
لوگوں کو اختیار دے دیتا ہے کہ اب تم چاہو تو اس ضابطہ عمل کو اختیار کرو اور چاہو تو اُسے
رڈ کر دو اور پھر جو اسے اختیار کرتا ہے اور جس حد تک اختیار کرتا ہے وہ اس حد تک اُس
کے برکات اور نیک اثرات سے مستفیض ہوتا ہے اور اپنے خدا کا قرب حاصل کرتا
ہے.اور جو اسے اختیار نہیں کرتا وہ ان باتوں سے محروم رہتا ہے.اور اس کی یہ محرومی ہی
گناہ اور جرم کے نام سے موسوم ہوتی ہے.پس گناہ کا وجود خدا کا پیدا کردہ نہیں ہے بلکہ
وہ انسان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے.لہذا اس کی وجہ سے خدا پر حرف گیری کرنا یا خدا
کے خلاف استدلال کرنا بالکل غلط اور باطل ہے.223
Page 224
خُدا نے تو انسان کی فطرت میں نیکی کا تم ودیعت کیا اور پھر اس تخم کی آبپاشی اور
پرورش اور ترقی کے لئے اپنے پاس سے شریعت نازل فرمائی اور نشانات اور آیات کے
ذریعہ لوگوں کو سمجھایا اور ان پر حجت پوری کی کہ قانون شریعت کی پابندی میں ہی ان کی
نجات اور فلاح ہے.باوجود اس کے اگر پھر بھی کوئی شخص خدا کی نازل کردہ شریعت پر
عمل پیرا نہ ہوتو یہ اس کا اپنا قصور ہو انہ کہ خُدا کا.اور اس کی محرومی خود اس کے اپنے فعل
کا نتیجہ ہوئی نہ کہ خدا کے فعل کا.گناہ کیا ہے؟ یہی کہ انسان خدا کے حکم کی نافرمانی کرے
اور جوطریق اس نے بتایا
ہے اس کے خلاف چلے.پس گناہ انسان کے اپنے فعل کا نتیجہ
ہے نہ کہ خدا کا.کیا خدا اس وجہ سے ہمیں ہدایت کا رستہ بتانے سے باز رہتا کہ بعض
لوگ اس ہدایت کو نہ مانیں گے؟ کیا ایک باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کرنے سے صرف اس
وجہ سے باز رہ سکتا ہے کہ شائد وہ میری نافرمانی کر کے مجرم بن جائے ؟ یہ نادانی اور
جہالت کی باتیں ہیں جس سے ہر عقلمند کو پر ہیز لازم ہے.خلاصہ کلام یہ کہ دنیا میں جو گناہ اور معاصم اور ایک دوسرے کے خلاف ظلم وستم
کے نظارے نظر آتے ہیں یہ لوگوں کے اپنے افعال
کا نتیجہ ہیں اور خدا پر اس کی قطعا کوئی
ذمہ داری نہیں اور نہ اس کی وجہ سے کوئی عقلمند خدا کی ہستی کے خلاف استدلال کر سکتا
ہے.خدا کی طرف سے تو سبرا سر رحمت ہی رحمت کا نزول ہوا ہے مگر جو شخص اس رحمت
سے
فائدہ نہیں اٹھاتا وہ اپنے فعل کا خود ذمہ دار ہے.اور اگر کوئی شخص یہ کہے کہ خدا نے شریعت کا قانون ایسا کیوں نہیں بنایا کہ کوئی
شخص اسے توڑ ہی نہ سکتا اور سب لوگ اس کے مطابق عمل کرنے پر مجبور ہوتے اور اس
طرح گناہ کا وجود نیا میں پیدا ہی نہ ہوسکتا اور سارے لوگ نیک اور پارسا ر ہتے تو اس کا
جواب یہ ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو انسان کے پیدا کرنے کی غرض ہی باطل چلی جاتی جو یہ
ہے کہ انسان اپنی کوشش اور جدو جہد سے اپنے لئے اعلیٰ ترقیات کے دروازے کھولے
224
Page 225
اور اپنے اعمال سے خدا تعالیٰ کے انعام و اکرام کا حقدار بن کر اس کا قرب حاصل
کرے.پس اگر ہر شخص مجبور ہوتا کہ خدا کی نازل کردہ شریعت کے مطابق اپنی زندگی
رکھے تو انسان کے لئے یہ سب ترقیات کے دروازے مسدود ہو جاتے اور کوئی شخص
انعام واکرام کا حقدار نہ بن سکتا اور یہ سارا سلسلہ جہد و عمل کا بریکار جاتا.خوب سوچ لو کہ
انعام کا حقدار بننے کے لئے یہ ضروری ہے کہ انسان صاحب اختیار ہو یعنی چاہے تو نیکی
کے رستے کو اختیار کرے اور چاہے تو بدی کے رستے پر چل پڑے.لیکن اگر انسان مجبور
ہو تو پھر یقینا نیکی سے محبت کرنے والے اور نیکی سے محبت نہ کرنے والے، ٹھیک رستے
پر چلنے والے اور ٹھیک رستے پر نہ چلنے والے، اپنے نفس پر قابورکھنے والے اور اپنے نفس
پر قابو نہ رکھنے والے، استقلال وصبر سے کام لینے والے اور استقلال وصبر سے کام نہ
لینے والے، محنت کرنے والے اور محنت نہ کرنے والے سب برابر ہو جاتے اور اچھے
بُرے میں کوئی امتیاز نہ رہتا.اسی طرح جو ترقی باہمی مقابلہ اور رشک اور مسابقت کے
خیال کی وجہ سے اس وقت حاصل ہو رہی ہے وہ بھی سب رُک جاتی اور ترقی کرنے کا
کوئی محرک دنیا میں باقی نہ رہتا اور انسان گویا ایک منجمد صورت اختیار کر لیتا یا زیادہ سے
زیادہ ایک فرشتہ کی طرح ہو جاتا جس کی نیکی دراصل کوئی نیکی کہلانے کی حقدار نہیں
کیونکہ وہ اپنی خلقت سے مجبور ہے کہ ٹھیک رستے پر چلے اور اس کے لئے یہ ممکن ہی نہیں
کہ خُدا کے منشاء سے ذرا بھی ادھر اُدھر ہو اور اسی لئے عقلمندوں کا قول ہے کہ فرشتہ کی
نسبت نیک انسان
کا مرتبہ بالا ہوتا ہے کیونکہ انسان اپنے سوچ بچار اور غور وفکر کے نتیجہ
میں نیکی اختیار کرتا ہے لیکن فرشتہ اپنی نیکی کی حالت میں بطور ایک قیدی کے محصور ہے
اور اس لئے اس
کی نیکی دراصل کوئی نیکی نہیں اور اسی لئے قرآن کریم نے بھی انسان کے
متعلق فرمایا ہے: لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيْمِ
سورة التين - آیت5
225
Page 226
یعنی ”ہم نے انسان کو جملہ مخلوقات میں سے بہترین فطرت کے ساتھ پیدا کیا
ہے اور کوئی دوسری مخلوق اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی.“
الغرض انسان کا اپنے اعمال میں صاحب اختیار ہونا اس کے کمال کی علامت ہے
اور گناہ کا وجود اس اختیار کے غلط استعمال
کا نتیجہ ہے.پس گناہ خدا کا پیدا کردہ نہیں ہے
بلکہ خدا کی رحمت کے انکار کا ثمرہ ہے.لہذا اس کا وجود خدا کی ہستی کے خلاف ہرگز بطور
دلیل کے پیش نہیں کیا جاسکتا.دہریت کی چھٹی دلیل اور اُس کا رڈ
چھٹی دلیل جو دہریوں کی طرف سے ہستی باری تعالیٰ کے خلاف پیش کی جاتی
ہے وہ بھی دلیل پنجم کی طرح قانون نیچر کے ایک فرضی اندھیر پر مبنی ہے.کہا جاتا ہے کہ
دنیا میں بعض ایسی چیزوں کا وجود پایا جاتا ہے کہ جن کا فائدہ کوئی نہیں ہے اور اُن کی
مضرت عیاں ہے.مثلاً یہ جو دُنیا میں بے شمار ضرررساں حیوانات اور ن
اور زہریلی
بیل بوٹیاں اور مہلک معاون پائے جاتے ہیں جن کا صرف نقصان ہی نقصان ہے اور
فائدہ کچھ بھی نہیں ان کا وجود ظاہر کرتا ہے کہ اس کائنات کے اوپر کوئی خدا نہیں ہے ورنہ
یہ چیزیں دنیا میں نہ پائی جاتیں.اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اعتراض معترضین کی جہالت
کا نتیجہ ہے کیونکہ اگر غور سے کام لیا جائے تو اس بات میں ذرہ بھر شک نہیں رہتا کہ دُنیا
کی کوئی چیز بھی در حقیقت بغیر کسی فائدہ اور غرض و غایت کے نہیں ہے اور یہ صرف انسان
کے اپنے علم کی کمی ہے کہ وہ بعض چیزوں کی غرض وغایت کو نہیں سمجھتا اور ان کے فائدہ
سے جاہل رہتا ہے اور صرف ظاہری طور پر ان کے بعض ضرر رساں اثرات کو دیکھ کر یہ
خیال کر لیتا ہے کہ ان چیزوں میں کوئی فائدہ نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ جو لوگ
حقائق الاشیاء کی تحقیق میں بڑھے ہوئے ہیں ان کی طرف سے ایسا اعتراض بہت کم ہوتا
226
Page 227
ہے اور صرف عامۃ الناس اس قسم کے شبہات کا شکار ہوتے ہیں.کیونکہ وہ بوجہ اپنی
جہالت کے حقائق الاشیاء سے بہت کم آگاہ ہوتے ہیں اور ان کی نظر اشیاء کی ظاہری
شکل وصورت اور ظاہری افعال واثرات سے آگے نہیں جاتی اور زیادہ باریک اور گہرا
مطالعہ انہیں میسر نہیں ہوتا.لیکن جو لوگ زیادہ وسیع مطالعہ رکھتے ہیں اور ان کی نظر ظاہر
سے گذر کر حقائق کی گہرائیوں تک پہنچنے کی عادی ہوتی ہے.وہ خوب سمجھتے ہیں کہ ہر چیز
اپنے اندر کوئی نہ کوئی فائدہ رکھتی ہے.اور یہ کہ جتنا کسی چیز کا زیادہ مطالعہ کیا جائے اتنا
ہی اس کے فوائد اور اس کی ہستی کی غرض و غایت زیادہ نمایاں طور پر نظر آنے لگتے ہیں
اور اسی لئے اگر ایسے لوگوں کو کسی چیز میں ایک وقت تک کوئی فائدہ نظر نہیں بھی آتا تو وہ یہ
خیال نہیں کرتے کہ اس کا وجود محض فضول اور باطل ہے.بلکہ وہ اس یقین پر قائم رہتے
ہیں کہ زیادہ گہرے مطالعہ سے آئندہ کسی وقت اس کے اندر بھی کوئی حکمت اور کوئی فائدہ
معلوم ہو جائے گا کیونکہ وہ بار بار کے تجربات سے یہ یقینی علم حاصل کر چکے ہوتے ہیں کہ
جو چیزیں ظاہری اور سرسری نظر میں بے فائدہ بلکہ ضرررساں نظر آتی ہیں ان کے اندر
بھی گہرے مطالعہ اور تحقیق سے بہت سے فوائد دریافت ہو جاتے ہیں.پس یہ اعتراض
محض جہالت کا اعتراض ہے اور حق یہی ہے کہ دُنیا کی ہر چیز اپنے اندر کوئی نہ کوئی حکمت
اور کوئی نہ کوئی فائدہ رکھتی ہے.اور حقائق الاشیاء کے مطالعہ میں انسان جتنا بھی ترقی
کرتا جاتا ہے اتنا ہی اس کے اندر یہ یقین زیادہ راسخ اور زیادہ بصیرت کے ساتھ قائم
ہوتا جاتا ہے کہ دُنیا کی کوئی چیز بھی باطل نہیں.افسوس ! معترضین اس بات کو بھی نہیں سوچتے کہ گذشتہ زمانوں میں جبکہ
حقائق الاشیاء کا علم بہت محدود تھا اور سائنس کے علوم کی طرف لوگوں کی توجہ بہت کم تھی
اُس وقت موجودہ زمانہ کی نسبت بہت زیادہ چیزیں ایسی تھیں جو بالکل بے فائدہ بلکہ
ضرر رساں نظر آتی تھیں لیکن حقائق الاشیاء کے علم اور سائنس کی تحقیقاتوں کی ترقی کی
227
Page 228
وجہ سے آج اُن میں سے بہت سی چیزوں کے اندر خاص فوائد نظر آرہے ہیں.اور ان
نقصانات کی بھی جدید علوم کی روشنی میں معقول تشریح کی جاسکتی ہے بلکہ یہ ثابت کیا
جاسکتا ہے کہ ان کی یہی ضرر رسانی بالواسطہ طور پر نسل انسانی کے لئے مفید ہے کیا یہ نظارہ
ایک عقلمند انسان کے خیال کو اس طرف مائل کرنے کے لئے کافی نہیں ہے کہ جو چیزیں
دُنیا میں آج بے فائدہ اور محض ضرر رساں نظر آرہی ہیں اُن میں سے بہت سی کل کو مخفی
فوائد سے معمور نظر آئیں گی اور پرسوں ان چیزوں کے متعلق علم و معرفت کا دائرہ اور بھی
وسیع ہو جائے گا.اور اسی طرح ہر روز نئے علوم اور نی تحقیقاتوں کے ذریعہ سے علم بڑھتا
جائے گا اور جہالت کم ہوتی جائے گی.جیسا کہ قرآن شریف اور احادیث میں بھی بیان
ہوا ہے کہ آخری زمانہ میں زمین و آسمان کے مخفی خزانے باہر نکل آئیں گے اور نئے نئے
علوم کی اشاعت ہوگی.پس اس سے بڑھ کر اور کیا جہالت ہوگی کہ کوئی شخص صرف اپنے
موجودہ علم کی بنا پر دنیا کی لاتعداد چیزوں کے حقائق اور ان کی سودمندی کا انکار کر دے
اور ان کی بعض ضرر رساں تاثیرات کی وجہ سے جو وہ بھی قدرت کی بار یک در بار یک
حکمتوں پر مبنی ہیں اور ان سے بالواسطہ طور پر بنی نوع انسان اور دیگر مخلوقات کو طرح
طرح کے منافع پہنچتے رہتے ہیں یہ خیال کرنے لگ جائے کہ ان چیزوں میں سوائے
ضرر رسانی کے اور کچھ نہیں.میں مثالیں دے کر اس مضمون کو طول دینا نہیں چاہتا والا میں بتاتا کہ کس طرح
حیوانات میں بھی اور نباتات میں بھی اور جمادات میں بھی ایسی چیزیں موجود ہیں جو آج
سے پہلے محض بے فائدہ نظر آتی تھیں اور سوائے ضرر رسانی کے ان کا اور کوئی کام نہیں
سمجھا جاتا تھا لیکن آج وہی چیزیں طرح طرح سے انسان کی خدمت میں لگی ہوئی نظر
آتی ہیں.حتی کہ سانپ اور بچھو اور مہلک بیماریوں کے جراثیم اور مختلف اقسام کے
خطرناک زہر وغیرہ بھی اس خدمت انسانی سے باہر نہیں اور کوئی دن ایسا نہیں چڑھتا
228
Page 229
جس میں قرآن شریف کے اس قول کی صداقت کہ خدا نے زمین و آسمان کی کسی چیز کو
باطل نہیں پیدا کیا.بیش از بیش وضاحت کے ساتھ ثابت نہ ہوتی جاتی ہو.دُنیا میں ضرر رساں چیزیں کیوں پیدا کی گئی ہیں؟
باقی رہا یہ اعتراض کہ اگر یہ درست ہے کہ خدا نے کسی چیز کو باطل نہیں پیدا کیا اور
ہر چیز انسان کے فائدہ کے لئے بنائی گئی ہے تو ان چیزوں کے ضرر رساں پہلو کیوں
رکھے گئے ہیں اور ایسا کیوں نہیں کیا گیا کہ تمام چیزیں ضرر رساں ہونے کے بغیر فائدہ
بخش ہوتیں؟ مثلاً سانپ سے جو فائدہ انسان کو یا دوسری مخلوق کو پہنچ سکتا تھا وہ کسی ایسے
رنگ میں پہنچایا جاتا کہ اس کے ساتھ کوئی ضرررساں پہلو نہ ہوتا.سو اس کا پہلا جواب تو
یہ ہے کہ خالق فطرت نے جس طرح مناسب سمجھا اس طرح کیا اور ہمارا یہ کام نہیں کہ
نیچر کے افعال کی تفاصیل کو زیر تنقید لائیں اور نہ ہم اس کے اہل ہیں بلکہ ہمارا کام صرف
یہ دیکھنا ہے کہ آیا جو کچھ دنیا میں ہورہا ہے وہ اُصولی اور مجموعی طور پر حق وانصاف اور
رحم و عدل پر مبنی ہے یا نہیں؟ لہذا جب یہ ثابت ہے کہ دُنیا کی کوئی چیز محض ضرر رساں نہیں
ہے بلکہ اس کے اندر یقینی فوائد مخفی ہیں اور جو چیزیں بے فائدہ اور محض ضرر رساں نظر آتی
ہیں وہ بھی درحقیقت ایسی نہیں بلکہ صرف ہمارے علم کی کمی کی وجہ سے وہ ہمیں ایسی نظر
آتی ہیں تو نیچر کی تفصیلات میں جا کر یہ سوالات اُٹھانا کہ فلاں چیز کو اس اس طرح
کیوں
بنایا گیا ہے اور اُس اُس طرح کیوں نہیں بنایا گیا ہر گز سلامت روی کا طریق نہیں
سمجھا جا سکتا.اور نہ کوئی عظمند یہ خیال کر سکتا ہے کہ جو شخص دوسری مخلوقات کی طرح اپنے
آپ کو بھی محض مخلوق خیال کرتا ہے وہ اُصول خلق و تکوین میں اس قدر تفصیلی نظر رکھ سکتا
ہے کہ ہر چیز کے متعلق وہ یقینی طور پر یہ بتا سکے کہ وہ اِس اِس اُصول کے ماتحت اس اس
سورة ص - آیت 28
229
Page 230
شکل وصورت میں بنائی گئی ہے.پس پہلا جواب تو میرا یہی ہے کہ جب اُصولی طور پر
ایک بات ثابت ہو جائے تو خواہ نخواہ ایک سوال کے اوپر دوسرا سوال جماتے چلے جانا
کہ یہ اس طرح کیوں ہے اور وہ اُس طرح کیوں نہیں ہے ہرگز سلامت روی کی راہ
نہیں ہے.پھر یہ بھی سوچنا چاہئے کہ اگر اس قسم کے تمام جزوی اور تفصیلی اعتراضات کے
حل ہو جانے پر ہی کوئی چیز قبول کی جانی چاہئے تو پھر کبھی بھی کسی بحث کا خاتمہ نہیں ہو سکتا
کیونکہ اس قسم کے سوالات کا سلسلہ غیر متناہی طور پر جاری رکھا جا سکتا ہے.پس عقلمندی
کی راہ یہی ہے کہ جب اُصولی طور پر ایک بات سمجھ آجائے تو خوہ اس کی بعض جزوی
تفصیلات حل نہ بھی ہوں تو اُسے قبول کر لیا جائے اور باقی کو حوالہ بخدا کیا جائے.اس کے بعد میں اصل جواب عرض کرتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ علاوہ اس کے کہ
بعض اشیاء کی ضرر رسانی اس رنگ میں فائدہ بخش ہے کہ وہ بعض مفید نتائج پیدا کرنے
میں مد ہوتی ہے.جیسا کہ مثلاً سانپ کا زہر بعض خطر ناک بیماریوں کے علاج میں کام
آتا ہے اور قانونِ نیچر کے ماتحت اس کا یہ فائدہ اس کے زہر ہونے کی خاصیت کے
ساتھ بطور لازم و ملزوم کے ہے.یہ ضرر رسانی اس رنگ میں بھی مفید اور نفع مند ہے کہ
اس سے بنی نوع انسان کی اخلاقی اصلاح اور مادی ترقی میں بالواسطہ طور پر بہت بڑی
مدد ملتی ہے.ہر عظمند میرے ساتھ اس بات میں اتفاق کرے گا کہ کبھی کبھی تکالیف اور
دُکھوں کا پیش آنا انسان کے اخلاق حسنہ کی عمارت کی تعمیل کے لئے از بس ضروری ہے
اور کوئی شخص جسے اپنی زندگی میں کبھی بھی کسی تکلیف اور دُکھ اور مصیبت کا سامنانہ ہو ا ہو
اپنے اخلاق میں کامل نہیں ہو سکتا.اور اسی طرح انسان کی مادی ترقی کے بھی بہت سے
پہلو تکالیف اور مصائب کے پیش آنے کے بغیر پوری نشو و نما نہیں پاسکتے.لہذا دُنیا میں
بعض چیزوں کا اپنے اندر ضرر رساں پہلو رکھنا بالواسطہ طور پر انسان ہی کے فائدہ اور
230
Page 231
ترقی کے لئے ہے اور کوئی عقلمند اس پر اعتراض نہیں کر سکتا اور یقیناً اس میں اور بھی بہت
سے
فوائد مخفی ہو نگے جن کو ابھی تک ہم معلوم نہیں کر سکے.اور اگر کسی کو یہ شبہ گذرے کہ اگر یہ ضرر رساں جانور وغیرہ واقعی مفید ہیں تو ان کو
نتباہ و برباد کیوں کیا جاتا ہے اور کیوں بعض صورتوں میں خود مذہب انسان کو یہ حکم دیتا ہے
کہ فلاں فلاں چیز کو ہلاک کرتے رہنا چاہیئے ؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قانون نیچر کا یہ
ایک عام قاعدہ ہے کہ وہ دُنیا میں ہر چیز کے متعلق ایک توازن قائم رکھنا چاہتا ہے اور
افراط اور تفریط کا طریق اس کے مسلک کے خلاف ہے.پس چونکہ جو چیزیں اپنے اندر
نمایاں طور پر ضرررساں پہلو بھی رکھتی ہیں اُن کا دُنیا میں حد اعتدال سے بڑھ جانا
بمقابلہ اُن کے فائدہ کے نقصان کا زیادہ موجب ہوسکتا ہے اور ان کے فائدہ کا پہلو
صرف اسی صورت میں غالب رہ سکتا ہے کہ اُن کی تعداد نیا میں زیادہ نہ بڑھنے پائے.اس لئے خدا تعالے نے کمال حکمت سے ایک طرف تو ان چیزوں کو دنیا میں پیدا کر دیا
اور دوسری طرف انسان کی طبیعت میں یہ بات ڈال دی اور بعض صورتوں میں صراحۃ
حکم بھی دے دیا کہ ان چیزوں کو دنیا میں زیادہ نہ پھیلنے دو.اور اس طرح نیچر کا فطری
توازن قائم کرلیا گیا.خلاصہ کلام یہ کہ دُنیا کی بعض چیزوں کا اپنے اندر ضرر رساں پہلو رکھنا ہرگز
موجب اعتراض نہیں ہو سکتا.اور حق یہی ہے کہ دنیا کی ہر چیز ایک خاص غرض و غایت
کے ماتحت پیدا کی گئی ہے اور بعض اشیاء کی ضرر رسانی بھی بالواسطہ طور پر انسان ہی کے
فائدہ کے لئے ہے.پس دہریوں کا یہ اعتراض بالکل فضول اور لغو ہے جس سے
معترضین کی جہالت کے سوا اور کوئی بات ثابت نہیں ہوسکتی.231
Page 232
دہریت کی ساتویں دلیل اور اس کا رو
فرائیڈ کے ایک نظریہ کا بطلان
ساتویں دلیل جو بعض دہریوں کی طرف سے خُدا کی ہستی کے خلاف پیش کی
جاتی ہے وہ یورپ کے بعض جدید محققین کے اس نظریہ پر مبنی ہے کہ خدا کا خیال دراصل
انسانی دماغ کا ایک رد عمل ہے.ان لوگوں کا خیال ہے کہ ایک بچہ جہاں ایک طرف
اپنے باپ کے ساتھ محبت کی مضبوط زنجیروں سے جکڑا ہوا ہوتا ہے اور اس کی طرف طبعی
میلان پاتا ہے اور اُسے نظر استحسان سے دیکھتا ہے اور اُسے اپنی حفاظت کا ذریعہ سمجھتا
ہے وہاں دوسری طرف وہ بچپن میں باپ سے ڈرتا بھی ہے اور اسے گویا اپنے لئے خطرہ
کا موجب سمجھتا ہے.لیکن ماں کے متعلق بچہ کے یہ خیالات نہیں ہوتے کیونکہ بچہ کے
لئے ماں براہِ راست خوراک کا ذریعہ ہوتی ہے اور ماں کے لئے اس کے جذبات بھی
زیادہ محبت اور زیادہ گرمجوشی کا رنگ رکھتے ہیں جو دوسرے تمام جذبات پر غالب رہتے
ہیں اور بچہ کبھی بھی اپنی ماں کو اپنے لئے ڈر اور خطرہ کا موجب نہیں سمجھتا اور ہر حالت
میں اس کی طرف لپکتا ہے اس لئے لڑکے اور ماں کے درمیان کبھی بھی اس قسم کے
رقابت اور مقابلہ کے جذبات نہیں پیدا ہوتے جو ایک ہوشیار اور ترقی کی خواہش رکھنے
والے لڑکے کے دل میں باپ کے متعلق آہستہ آہستہ غیر محسوس رنگ میں پیدا ہو سکتے
ہیں.ان رقابت کے جذبات اور اس خاموش مقابلہ کی رُوح کے لئے بعض مغربی
محققین نے اوایڈی پس کامپلیکس (Oedipus Complex) کی اصطلاح قائم
کی ہے جو ایک قدیم یونانی کہانی پر مبنی ہے جس میں ایک نو جوان اوایڈی پس نامی نے
اپنے باپ کو لاعلمی میں قتل کر دیا تھا اور پھر لاعلمی میں ہی اپنی ماں کے ساتھ شادی بھی کر
لی تھی.بہر حال ان محققین کا یہ خیال ہے کہ جب ایک طرف ایک لڑکا اپنے باپ کے
232
Page 233
لئے ایک گونہ رقابت کے جذبات قائم کر لیتا ہے اور اس سے ڈرتا ہے اور دوسری طرف
اس کے دل میں باپ کی فطری محبت بھی جاگزین ہوتی ہے اور وہ اسے اپنی حفاظت کا
ذریعہ بھی سمجھتا ہے تو اس کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ بڑے ہو کر جبکہ وہ باپ کے ابتدائی اثر سے
باہر نکلتا ہے تو وہ اپنے ذہن میں جو باپ بیٹے کے تصور میں پختہ ہو چکا ہوتا ہے ایک کمی
یعنی خلا سا محسوس کرنے لگتا ہے.اور یہ خلا اُسے بالآخر ایک ایسی خیالی ہستی کی طرف
کھینچ کر لے جاتا ہے جو اس کے لئے باپ کے تصور کی قائم مقام بن سکے اور یہی خیالی
ہستی آخر کار اس کے ذہن میں ایک بالا ہستی یعنی خدا کا رنگ اختیار کر لیتی ہے
وغیرہ وغیرہ.یہ نظریہ زیادہ تر یورپ کے مشہور فلاسفر اور نامور سائنس دان سگمنڈ فرائیڈ کا
پیش کردہ ہے جو 1856ء میں آسٹریا کے ایک یہودی خاندان میں پیدا ہوا اور بالآخر
اپنے آبائی وطن کو چھوڑ کر انگلستان چلا گیا اور بالآخر 1954ء میں فوت ہو گیا.فرائیڈ
بہت سی کتابوں کا مصنف ہے اور علم النفس کے مضمون میں خصوصیت کے ساتھ ماہر سمجھا
جاتا ہے.چنانچہ خدا کے تصور اور خوابوں وغیرہ کے فلسفہ کے متعلق اس نے اسی جہت
سے اعتراضات کئے ہیں.بہر حال زیر بحث نظریہ کے تعلق میں فرائیڈ کے اپنے الفاظ
یہ ہیں :
” ہاں جو بھوک کے وقت بچہ کے لئے تسکین کا باعث ہوتی ہے بچہ کی محبت کا
پہلا مرکز بنتی ہے.اور اسی طرح وہ تمام غیر معلوم اور آئندہ پیش آنے والے خارجی
خطرات کے مقابل پر بھی بچہ کے لئے تحفظ کا باعث بن جاتی ہے اور ہر قسم کے خوف اور
تشویش کے خلاف اس کے لئے جائے پناہ ہوتی ہے.مگر اس فعل میں جلدی ہی ماں کی
جگہ اس کا نسبتاً مضبوط تر باپ لے لیتا ہے اور یہ حالت زمانہ طفولیت کے اختتام تک
برابر قائم رہتی ہے.یہ فرزندانہ تعلق ایک مخصوص قسم کے ملے جلے جذبات سے متاثر ہوتا
233
Page 234
ہے.شروع میں ماں کے ساتھ اپنے ابتدائی محبت اور حفاظت کے تعلقات کی وجہ سے
بچہ کے لئے خود باپ بھی ایک گونہ خطرہ اور خوف کا رنگ رکھتا تھا اس لئے اس ابتدائی
طفولیت کے زمانہ میں وہ اگر ایک طرف اس سے محبت کرتا اور اسے نبظر استحسان دیکھتا
ہے تو دوسری طرف اسی نسبت سے اس سے ڈرتا بھی ہے....جب اس ماحول میں بچہ
بڑا ہوتا ہے اور محسوس کرتا ہے کہ اس کے لئے بچپن کی یہ کیفیت ہمیشہ کے لئے مقدر
ہو چکی ہے اور بغیر کسی خارجی مدد اور حفاظت کے انتظام کے اس کے لئے غیر معلوم اور
غالب طاقتوں کا مقابلہ ممکن نہیں تو وہ ان غیر معلوم اور غالب طاقتوں کو ہی باپ کے
تصوّروالی صفات کے ساتھ متصف کر دیتا ہے اور اپنے لئے ایسے خداؤں کا وجود تراش
لیتا ہے جن سے وہ ڈرتا بھی ہے اور جنہیں راضی بھی رکھنا چاہتا ہے اور جنہیں وہ اپنی
حفاظت کا ذریعہ بھی ٹھہراتا ہے.پس خدا کے تصور کی یہ توجیہہ کہ بچہ بڑا ہو کر بھی اپنے
باپ کا تصور قائم رکھنا چاہتا ہے اور اس دوسری تو جیہہ کے عین مطابق اور گویا اسی کی
دوسری صورت ہے کہ اسے انسانی کمزوریوں کے نتائج سے بچنے کے لئے خارجی
حفاظت کی ضرورت محسوس ہوتی ہے.الغرض بچہ کا بچپن میں اپنی بے بسی کے خلاف
مدافعانہ رد عمل اس کی پختگی اور جوانی کے زمانہ میں اسی احساس بے بسی کے رد عمل کو
ایک مخصوص ہیئت میں ڈھال دیتا ہے اور یہی تبدیلی مذہب اور خدا کے تصور کی اصل
بنیاد ہے“.دوسرے مقامات پر فرائیڈ نے اپنے اس نظریہ کی مزید تشریحات بھی کی ہیں اور
اوایڈی پس کامپلکس (Oedipus Complex) کے متعلق بھی بہت کچھ لکھا ہے
اور گوفرائیڈ کے اس نظریہ کو خود کئی دوسرے مغربی محققین نے قابل قبول نہیں سمجھا مگر
ضروری ہے کہ ہم اس جگہ مختصر طور پر اس اعتراض کا اُصولی جواب بھی درج کر دیں جو
فیوچر آف این الوژن صفحہ 42,41 مصنفہ سگمنڈ فرائیڈ
234
Page 235
اس نظریہ اور اس کے شاخسانوں پر مبنی ہے.سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہئے کہ یہ نظریہ دراصل اس نظریے کی ایک فرع ہے
جو ہم ” قبولیت عامہ کی دلیل کی بحث کے ضمن میں کتاب کے ابتدائی حصہ میں درج
کر چکے ہیں اور جس کی بنیاد دراصل اس جذبہ پر مبنی ہے جو عرف عام میں انفی ری
آری کامپلکس (Inferioirity Complex) کے نام سے مشہور ہے یعنی کسی زیادہ
طاقتور ہستی کے مقابل پر اپنی کمزوری اور فروما ئیگی اور اس طاقتور ہستی کی برتری اور
بلند مقامی کا احساس.اور اس لحاظ سے ہمارا وہ اصولی جواب جو ہم مذکورہ بالا بحث کے
دوران میں درج کر چکے ہیں کافی وشافی ہونا چاہیئے اور اس جگہ اس کے اعادہ کی
ضرورت نہیں.(دیکھو کتاب ہذا صفحہ 120 تا 122 ) مگر فرائیڈ کے اس مخصوص نظریہ
کے متعلق یہ بات خاص طور پر قابل نوٹ ہے کہ خواہ خود فرائیڈ کو اس بات کا احساس ہوا
ہو یا نہ ہوا ہو کیونکہ وہ خود یہودی تھا مگر دراصل فرائیڈ کا یہ خیال مسیحیت کی تعلیم سے
پیدا شدہ معلوم ہوتا ہے کیونکہ فرائیڈ نے اسی ماحول میں زندگی گزاری تھی.چونکہ
حضرت مسیح ناصری کی تعلیم میں یہودیت کے خشک فلسفہ مذہب کے مقابلہ پر خدا کو
استعارہ باپ کی صورت میں پیش کیا گیا ہے اور بعد میں آنے والے مسیحیوں نے تو
سچ سچ خُدا کو باپ قرار دے کر مسیح کو نعوذ باللہ اُس کا خود زادہ جنسی بیٹا تسلیم کیا ہے اور مسیحی
ممالک اور مسیحی سوسائٹی میں یہ باپ بیٹے کا تصور ایک نہایت درجہ شائع اور متعارف
چیز ہے.اس لئے فرائیڈ کا دماغ بھی باوجود یہودی النسل ہونے کے اور پھر با وجود ایک
قابل سائنسدان اور علم النفس کے ماہر ہونے کے اپنے ماحول کے تاثر سے آزاد نہیں
ہو سکا.اور چونکہ وہ عیسائی نہیں تھا اس لئے تعجب نہیں کہ اس نے اپنے خیال میں حضرت
مسیح ناصری کو بھی اسی احساس کمتری (Inferiority Complex) کا شکار سمجھ لیا ہو.اس ایڈیشن کے صفحات 120 تا 123 (پبلشرز )
235
Page 236
بہر حال یہ سارا قصہ صرف ”اے روسٹی طبع تو بر من بلاشدی کا کرشمہ نظر آتا ہے اور
اس کے سوا کچھ نہیں.مشکل یہ ہے کہ بعض اوقات سمجھدار لوگ بھی امکان اور واقعہ میں فرق نہیں
کرتے.وہ اپنے ذہنی تگ ودو کے نتیجہ میں ایک بات کے امکان کی وجوہات تلاش
کرتے ہیں اور جب بزعم خود وہ اس خیال پر قائم ہو جاتے ہیں کہ فلاں بات امکانی طور
پر اس اس رنگ میں ہو سکتی ہے تو پھر بسا اوقات آنکھ بند کر کے اس نتیجہ کی طرف کود
جاتے ہیں کہ بس وہ اسی طرح ہوئی ہوگی.حالانکہ ظاہر ہے کہ ایک بات کا امکان اور
چیز ہے اور اس کا عملاً وقوع میں آنا اور چیز ہے.دُنیا میں لاکھوں باتوں کا امکان موجود
ہے، مگر ان میں سے
کتنی ہیں جو عملاً بھی اسی طرح وقوع میں آتی ہیں جس طرح عقلی رنگ
میں ان کا امکان سمجھا جا سکتا ہے.پس محض کسی بات کے امکان سے اس کے عملاً وقوع
میں آنے کا استدلال کرنا ایک نادانی کا استدلال ہے.لہذا پہلا جواب تو اس اعتراض کا
یہ ہے کہ اگر بالفرض یہ بات مان بھی لی جائے کہ ایک بیٹے کے دل میں کبھی کبھی
غیر محسوس طور پر اپنے باپ کے متعلق رقابت کے جذبات پیدا ہو سکتے ہیں اور بالفرض یہ
بات بھی تسلیم کر لی جائے کہ ان رقابتی جذبات کے نتیجہ میں وہ بڑے ہو کر کبھی کبھی اپنے
ذہن میں ایک کمی اور خلا محسوس کر سکتا ہے کیونکہ اُسے اپنے بچپن والے باپ کے تصور کی
تلاش رہتی ہے اور پھر بالفرض یہ خیال بھی قبول کر لیا جائے کہ یہ ذہنی خلا اُسے کبھی کبھی کسی
بالا ہستی کے تصور کی طرف لے جاسکتا ہے جو اس کے لئے باپ کے تصور کی قائم مقام
ہو سکے تو باوجود ان دُور اُفتادہ امکانات کے یہ بات کیسے ثابت ہو گئی کہ دُنیا کی تمام قوموں
میں جو دُنیا کے مختلف حصوں اور مختلف زمانوں میں گذری ہیں اور جو کم از کم ابتدائی زمانہ
میں ایک دوسرے سے انتہائی حجاب اور دُوری کی حالت میں پڑی ہوئی تھیں ہمیشہ
بلا استثناء یہی امکانی صورت عملاً بھی اسی تفصیل کے ساتھ وقوع میں آتی رہی ہے؟
236
Page 237
پھر لطف یہ ہے کہ یہ سارے امکانات اگر انہیں درست بھی تسلیم کر
اپنے مقابل کے امکانات کے سامنے بالکل کمزور اور بعید از قیاس حیثیت رکھتے ہیں.مثلاً اگر یہ درست بھی ہو کہ ایک بیٹا بعض حالات میں امکانی طور پر اپنے باپ کے متعلق
رقابت کے جذبات پیدا کر سکتا ہے تو پھر بھی یہ ظاہر ہے اور دنیا میں ہمارا عملی تجر بہ اس پر
شاہد ہے کہ یہ صورت نہایت درجہ شاذ طور پر پیدا ہوتی ہے اور بیشتر بلکہ کثیر طور پر بیشتر
صورتوں میں طبعی طریق یہی ہے کہ بیٹا ہر حال میں اپنے باپ کا محب اور وفادار رہتا ہے
اور اگر وہ علمی یا عملی میدان میں اپنے باپ سے آگے بھی نکل جاتا ہے تو پھر بھی اس کی
فطری محبت اور فطری وفاداری اُس کی آنکھوں کو باپ کے سامنے ہمیشہ نیچا رکھتی ہے.پس مزعومہ امکان نہایت ہی بعید از قیاس ہے اور یہی حال مغربی محققین کے دوسرے
مزعومہ امکانات کا ہے.پس عام حالات میں رقابت اور ذہنی خلا کا نظریہ ایک خیالی
بت سے زیادہ حقیقت نہیں رکھتا جسے توڑنے کے لئے کسی زیادہ ٹھوکر کی ضرورت نہیں.ایک طبعی اور فطری شاہراہ کو چھوڑ کر جو اپنے پہلو میں ایک آدھ غیر طبعی پگڈنڈی کی استثناء
سے زیادہ نہیں پیش کر سکتا ایک دُور اُفتادہ فرضی امکان کی آڑ لے کر خدا کی ہستی کا انکار
کرنا جسے جیسا کہ ہم قبولیت عامہ اور شہادت صالحین کی بحثوں میں ثابت کر چکے ہیں
(دیکھو کتاب ہذا صفحہ 143 تا 148 ) ، ہر قوم اور ہر ملک اور ہر زمانہ میں تسلیم کیا گیا ہے
خواہش نفس (Wishful Thinking) کے سوا کچھ نہیں.اور صاف نظر آ رہا ہے کہ
جن لوگوں نے یہ دلیلیں پیش کی ہیں انہوں نے اپنے مادی ماحول میں خُدا کی ہستی کا
انکار پہلے کیا ہے اور دلیلیں بعد میں سوچی ہیں.حق یہ ہے کہ جس احساس کمتری (Inferiority Complex) کو بعض
محققین نے ہستی باری تعالیٰ کے خلاف دلیل قرار دیا ہے وہ دراصل خدا کی ہستی کی ایک
اس ایڈیشن کے صفحات 120 تا 148 (پبلشرز )
237
Page 238
بھاری دلیل ہے جسے مسلمان محقق اوائل سے خدا تعالے کی ہستی کے ثبوت میں پیش
کرتے آئے ہیں.چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے خلیفہ حضرت علی
کرم اللہ وجھہ کا مشہور قول ہے کہ:.عَرَفْتُ رَبِّي بِفَسْخِ الْعَزَائِمِ
یعنی ” میں نے اپنے خُدا کو بڑے بڑے پختہ ارادوں اور مضبوط تدبیروں کے
ٹوٹنے اور ناکام رہنے کے ذریعہ سے پہچانا ہے.“
حضرت علیؓ کے اس بظاہر مختصر مگر باطن معانی سے لبریز قول میں وہی فلسفہ مخفی
ہے جسے دوسرے لفظوں میں آجکل کے بعض رُوحانیت سے نا آشنا لوگ احساس کمتری
(Inferiority Complex) کی اصطلاح کے نیچے لا کر ہستی باری تعالیٰ کے خلاف
استدلال کرتے ہیں.حضرت علیؓ کے قول کا مطلب یہ ہے کہ انسان بعض اوقات اپنے
کسی مقصد کے حصول کے لئے بڑے بڑے پختہ ارادے قائم کرتا ہے اور مضبوط ترین
تدبیروں کے ذریعہ تمام ان اسباب کو جمع کر لیتا ہے جو اس معاملہ میں کامیابی کے لئے
بظاہر ضروری ہوتے ہیں.حتی کہ کوئی درمیانی روک باقی نہیں رہتی اور اس کے بعد وہ
سمجھتا ہے کہ بس اب مجھے یہ مقصد حاصل ہو گیا کہ اچانک پردہ غیب سے ایسے حالات
ظاہر ہو جاتے ہیں جو اس کی پختہ تدبیروں کےتار پود کو بکھیر کر رکھدیتے ہیں اور اس کے
عزائم کی چٹان پاش پاش ہو کر گر جاتی ہے.اس وقت عقلمند انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس دنیا
میں صرف ظاہری عزم اور ظاہری تدبیر ہی آخری چیز نہیں ہے بلکہ انسانی تدبیروں سے
بالا اور اس کے عزائم سے مضبوط تر ایک اور ہستی بھی ہے جس کے سامنے انسان اپنی
انتہائی عقل و دانش اور اپنے وسیع سازوسامان کے باوجود ایک مردہ کیڑے سے زیادہ
حیثیت نہیں رکھتا.اور یہی وہ احساس کمتری ہے جس سے دُنیا کے
سمجھدار لوگ ہمیشہ خدا
کی طرف رہنمائی پاتے رہے ہیں.مگر افسوس ہے کہ اسی سے مغرب کے مادہ پرست
238
Page 239
محققین نے اپنے لئے ٹھوکر کا سامان مہیا کر رکھا ہے.عزیز و! خوب سوچو اور غور کرو کہ زائد حصوں کو الگ کر کے فرائیڈ اور اُس کے
ہم خیال محققین کی دلیل کا حقیقی خلاصہ اور مرکزی نقطہ سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ
انسان فطرۃ ایک بالا اور زیادہ طاقتور ہستی کا متلاشی ہے جسے وہ بطور نمونہ یعنی ماڈل اپنے
سامنے رکھ سکے اور جس کے غالب علم اور غالب قدرت کے سامنے وہ مرعوب ہو اور
اسے اپنی حفاظت کا ذریعہ سمجھے.اور جب اُن کی دلیل کا مرکزی نقطہ یہ ہے تو ظاہر ہے
کہ یہ دلیل ہستی باری تعالیٰ کے حق میں ہے نہ کہ اس کے خلاف.اور کتاب ہذا کے
ابتدائی حصہ میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ خود قرآن شریف نے اس دلیل کو فطری دلیل کی
صورت میں خدا کی ہستی کے ثبوت میں پیش کیا ہے ( ملاحظہ ہو کتاب ہذا صفحہ 47 تا
54 پس یہ دعویٰ کہ باپ کے تصور کی وجہ سے بیٹے کے دل میں بڑے ہو کر ایک ذہنی
خلا پیدا ہو جاتا ہے جسے پُر کرنے کے لئے وہ آہستہ آہستہ ایک خیالی خدا کا تصور پیدا
کر لیتا ہے ایک محض ہوائی دعوی ہے جو کچی فطرت انسانی اور دنیا کے وسیع مشاہدہ کے
خلاف ہے.ہاں بیشک یہ درست ہے کہ خدا کے ایمان کے بغیر فطرتِ انسانی میں ایک
خلاضرور رہتا ہے اور یہی وہ خلا ہے جو سعید لوگوں کو بالآخر بچے خدا کی طرف کھینچ لاتا
ہے.الغرض جس جہت سے بھی دیکھا جائے دہریت کی یہ دلیل جو فرائیڈ اور اس کے
ہم خیالوں کی طرف سے پیش کی گئی ہے ایک فلسفیانہ تخیل کے سوا کچھ نہیں.بلکہ حق یہ
ہے کہ یہ دلیل اپنی اصلی صورت میں ہستی باری تعالیٰ کے حق میں ہے نہ کہ اس کے
خلاف.اور یہی وجہ ہے کہ کئی دوسرے مغربی محققین نے دہریت کے اس استدلال کو
قابل قبول نہیں سمجھا اور اسے رڈ کیا ہے.یہ وہ سات اُصولی دلیلیں ہیں جو د ہریوں کی طرف سے عام طور پر اپنے عقیدہ کی
اس ایڈیشن کے صفحات 50 تا 57 (پبلشرز )
239
Page 240
تائید میں پیش کی جاتی ہیں مگر یہ سب دلیلیں ایک خیال کے لوگوں کی نہیں ہیں بلکہ مختلف
خیال کے لوگوں کی پیش کردہ ہیں اور اسی لئے ان میں سے بعض ایک دوسرے سے
ٹکراتی ہیں.یعنی ایک کے قبول کرنے سے دوسری کو رڈ کرنا پڑتا ہے.لیکن چونکہ مجھے
ہر خیال کے دہریوں کی تردید مقصود تھی اس لئے میں نے سب
قسم کے دلائل کو جمع کر دیا
ہے اور میں اُمید کرتا ہوں کہ ان سات اُصولی دلائل کا جواب سمجھنے کے بعد ہر فہمیدہ شخص
دہریوں کے عام اعتراضات کا جواب دے سکنے کے قابل ہو سکے گا.دراصل حق یہی
ہے کہ دہریوں کے ہاتھ میں کوئی دلیل نہیں ہے اور ان کے انکار کی اصل بنیاد صرف اس
بات پر ہے کہ اُن کے خیال میں ابھی تک اُن کے سامنے ہستی باری تعالیٰ کی کوئی ایسی
دلیل نہیں آئی جو ان کے دل میں یقین اور اطمینان پیدا کر سکے.اور اسی لئے اُن میں
سے جو لوگ نسبتاً فہمیدہ ہیں وہ کبھی بھی مثبت صورت میں یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ کوئی خدا
نہیں ہے کیونکہ اس دعویٰ سے اُن کے اوپر ایک ایسی ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے جسے وہ
ہرگز نبھا نہیں سکتے بلکہ وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس خدا کے موجود ہونے کا کوئی
ثبوت نہیں.لیکن جن لوگوں نے میرے اس مضمون کو نیک نیتی اور غور سے پڑھا ہے وہ
اس بات کو ضرور سمجھ گئے ہونگے کہ عقلی دلائل کے دائرہ میں بھی خدا کی ہستی کی تائید
والے دلائل کا پہلو اس قدر غالب ضرور ہے کہ انہیں سمجھ لینے کے بعد کوئی عقلمند انسان
کم از کم خدا کی ہستی کا منکر نہیں رہ سکتا.اور در حقیقت جیسا کہ میں نے شروع مضمون
میں تصریح کے ساتھ بیان کیا تھا عقلی دلائل کی پہنچ بھی صرف اسی حد تک ہے کہ وہ خدا
کے موجود ہونے کے متعلق ایک ابتدائی مرتبہ یقین کا پیدا کر دیں مگر کامل اور قطعی یقین
ان دلائل سے پیدا نہیں ہو سکتا بلکہ اس کے لئے دوسری قسم کے دلائل کی ضرورت ہے جو
تجربہ اور مشاہدہ سے تعلق رکھتے ہیں اور جن کا علم ہمیں انبیاء اور صلحاء کے معجزات اور
نشانات سے حاصل ہوتا ہے.240
Page 241
کمیونزم اور خُدا کا عقیدہ
اس مضمون کو ختم کرنے سے قبل کمیونزم یعنی روس کے موجودہ اشتراکی نظام کے
متعلق بھی کچھ بیان کرنا ضروری ہے کیونکہ بعض لوگ اس نظام کو بھی دہریت کی ایک
شاخ اور ہستی باری تعالیٰ کے انکاری ثبوتوں میں سے ایک ثبوت قرار دیتے ہیں.حالانکہ غور کیا جائے تو یہ اشتراکی نظام ایک محض اقتصادی نظام ہے، جسے حقیقۂ خدا کے
موجود ہونے یا نہ ہونے کے سوال کے ساتھ کوئی طبعی تعلق نہیں ہے.مگر جس طرح مسئلہ
ارتقاء کو بعض جلد باز لوگوں نے ہستی باری تعالیٰ کے خلاف قرار دے لیا تھا اسی طرح
کمیونزم کو بھی بعض کو تہ اندیش لوگ خدا کی ہستی کے خلاف سمجھنے لگ گئے ہیں.حالانکہ
قطع نظر اس کے کہ کمیونزم کے اُصول درست ہیں یا غلط یا کس حد تک درست ہیں اور
کس حد تک غلط اُسے ہستی باری تعالیٰ کے سوال کے ساتھ کوئی طبعی جوڑ نہیں ہے بلکہ وہ
محض ایک اقتصادی نظام ہے جس کے ذریعہ روس نے ذرائع آمد و پیداوار کو حکومت
کے ہاتھ میں لے کر بزعم خود اپنے ملک کی دولت منصفانہ رنگ میں تقسیم کرنے کی کوشش
کی ہے.اور گو اُس نے اس کوشش میں ٹھوکر کھائی ہے جس کا ضرر رساں اثر مخفی صورت
میں تو اب بھی محسوس ہو رہا ہے، جس کی اشترا کی نظام میں آئے دن کی تبدیلیاں شاہد
ہیں مگر ظاہراً اور بدیہی طور پر اس کا ضرر رساں اثر چند نسلوں کے بعد ظاہر ہوگا کیونکہ
ایسے وسیع نظاموں کا اثر فوری طور پر نظر نہیں آیا کرتا.مگر بہر حال وہ ایک محض اقتصادی
نظام ہے جسے وجود باری تعالیٰ کے سوال کے ساتھ کوئی تعلق نہیں مگر چونکہ اس نظام نے
ملک کے موجودہ نظاموں کو تو ڑ کر اپنی جگہ بنائی ہے اور موجودہ نظاموں میں وہ نظام بھی
شامل ہیں جو مختلف مذاہب کی طرف منسوب ہوتے ہیں اس لئے اس نظام کا بظاہر
مذاہب کی تعلیم کے ساتھ ٹکراؤ پیدا ہو گیا ہے.اب کراؤ کی دور امام موسی کمیونزم کے لیڈروں نے روس کے
ہوئی ہے
241
Page 242
بچوں اور نو جوانوں کے دماغوں کو کمیونزم کے اثر سے پوری طرح متاثر کرنے کے لئے
یہ تدبیر اختیار کی ہے کہ اپنے سکولوں اور درسگاہوں میں مذہبی تعلیم کو بالکل ہی اُڑا دیا ہے
تا کہ کوئی بچہ ایسے خیالات سے متاثر نہ ہو سکے جو کسی رنگ میں بھی اشتراکیت کے اُصول
کے خلاف ہوں.اور اس طرح نتیجہ ملک میں دہریت کا دور دورہ شروع ہو گیا ہے مگر یہ
دہریت کمیونزم کا حصہ نہیں ہے بلکہ اس کے گردو پیش کے حالات
کا ایک طبعی نتیجہ ہے اور
بہر حال فی ذاتہ کمیونزم کے اندر کوئی ایسی بات نہیں جو ہستی باری تعالیٰ کے خلاف
براہ راست دلیل کا رنگ رکھتی ہو.بیشک موجودہ اشتراکیت کا نظام اپنی کئی اصولی باتوں
اور کئی تفصیلات میں معروف مذاہب کی تعلیم کے خلاف ہے اور عقلی طور پر بھی اس کے
خمیر میں کئی ایسے ضرر رساں عناصر پائے جاتے ہیں جو گوفی الحال نہیں مگر چند نسلوں کے
بعد اپنی بھیانک خرابیوں کو برملا ظاہر کرنا شروع کر دینگے مگر بہر حال اشتراکیت کا بنیادی
اُصول اقتصادی ہے نہ کہ روحانی یا مذ ہیں.لہذا اسے دہریت کے ثبوت میں پیش کرنا کسی
طرح درست نہیں.دراصل سینکڑوں سال سے یورپ کا اقتصادی نظام ایسے راستہ پر چل رہا تھا کہ
قوموں اور ملکوں کی دولت سمٹ سمٹ کر ایک خاص سرمایہ دار طبقہ کے ہاتھوں میں جمع
ہوگئی تھی اور آبادیوں کا بقیہ حصہ غربت و افلاس کے بھنور میں پھنس کر آہستہ آہستہ ایسی
حالت کو پہنچ گیا تھا کہ جب تک موجودہ نظام کو کسی دلیرانہ اقدام کے ساتھ بدلا نہ جاتا
اس کی زندگی جانوروں سے بہتر نہیں تھی.اور یہ حالت سب سے زیادہ بھیا نک صورت
میں روس میں رونما تھی جہاں زاروں کی استبدادی حکومت اور امیروں کے تعیش نے
غریبوں کا گویا گلا گھونٹ رکھا تھا.پس جیسا کہ ہر لمبے ظالمانہ نظام کا ایک رد عمل ہو ا کرتا
ہے جو گویا قائم شدہ نظام کے خلاف بغاوت کا رنگ رکھتا ہے اسی طرح روس کے ملک
میں سابقہ ظالمانہ نظام کا رد عمل اشتراکیت کی صورت میں ظاہر ہوا جس نے ملک کے
242
Page 243
اندر ایک خطرناک انقلاب پیدا کر کے ایک نئے نظام کی بنیاد قائم کر دی.اس نئے نظام
میں زاروں کا سلسلہ اڑا ، نوابوں کی نوابیاں ختم ہوئیں، امیروں کی امارت گئی اور آئندہ
کے واسطے ملک کی دولت کی بظاہر مساویانہ تقسیم کے لئے ایک وسیع اشترا کی نظام جاری
کر دیا گیا.مگر جس طرح ہر رد عمل اور ہر بغاوت کے فعل میں جو کسی قائم شدہ نظام کے
خلاف ہو دوسری انتہا کی طرف جھک جانے کا میلان ہوا کرتا ہے اسی طرح اشتراکیت
والا رد عمل بھی ایک انتہا سے باغی ہو کر دوسری انتہا کو پہنچ گیا ہے اور ظاہر ہے کہ جس
طرح ایک طرف کی انتہا نقصان دہ اور ضرر رساں تھی اسی طرح دوسری طرف کی انتہا بھی
بھاری خطرات سے معمور ہے.گو یہ علیحدہ بات ہے کہ وقتی جوش کے ماتحت یہ خطرات
اس وقت کھلے طور پر نظر نہ آئیں اور مختصر طور پر یہ خطرات مندرجہ ذیل ہیں :.1.کمیونزم نے دولت اور دولت پیدا کرنے کے ذرائع کو کلیتہ حکومت کے ہاتھ
میں دیگر انفرادی جدو جہد کے سب سے بڑے محرک کو تباہ کر دیا ہے.ظاہر ہے کہ گو دُنیا
میں کام کے محترک بے شمار ہیں مگر وہ محترک جو تمام محرکات سے وسیع تر ہے اور ہر طبقہ اور
ہر درجہ کے لوگوں میں یکساں پایا جاتا ہے اور فطرتِ انسانی کا ایک حصہ ہے وہ اس شوق
اور اس جذبہ سے تعلق رکھتا ہے کہ انسان اپنی محنت کا پھل خود براہ راست بھی کھائے
اور یہ شوق اور یہ جذ بہ اشتراکیت کے نظام نے بالکل کچل ڈالا ہے.بیشک ہر شریف
انسان میں یہ جذبہ بھی ہوتا ہے اور ضرور ہونا چاہئے کہ وہ دوسروں کا ہاتھ بٹائے اور اپنے
مال اور اپنے وقت کا کچھ حصہ ان کے لئے بھی خرچ کرے اور اسلام نے تو اس
مؤخر الذکر جذبہ پر بہت زیادہ زور دیا ہے.مگر پھر بھی یہ خیال کہ اس کی محنت کا پھل
زیادہ تر خود اسی کو حاصل ہوگا انسان کے لئے کام کا بہت بڑا فطری محترک ہے.مگر
اشتراکیت نے اس محترک کو تباہ کر کے انسانی ترقی کی رفتار کو سست کرنے کا رستہ کھول
دیا ہے.243
Page 244
2.کمیونزم کے نظام میں دوسرا بھاری نقص یہ ہے کہ بوجہ اس کے کہ دولت پیدا
کرنے کے سارے ذرائع حکومت کے ہاتھ میں چلے گئے ہیں لوگوں میں آہستہ آہستہ
مقابلہ اور مسابقت کی رُوح کمزور ہونی شروع ہو جائے گی اور چونکہ بنی نوع انسان کی
ترقی میں مسابقت کی رُوح کو بھاری دخل ہے اس لئے اس تبدیلی کا لازمی نتیجہ آہستہ
آہستہ قومی تنزل کی صورت میں ظاہر ہو گا.مثلاً جہاں کئی کمپنیاں یا کئی لوگ موٹر کاروں یا
ہوائی جہازوں کے الگ الگ کارخانے جاری کر کے اور الگ الگ محنت اور
دماغ سوزی کر کے اس صنعت کو فروغ دینے کے درپے ہو نگے اور اُن کے درمیان
جائز رقابت اور مقابلہ اور مسابقت کی روح بھی قائم ہوگی اور ساتھ ساتھ اس صنعت کا
کچھ حصہ حکومت کے ہاتھ میں بھی ہو گا وہاں لا ز ما یہ صنعت بہت زیادہ ترقی کر جائے گی
اور اس کے مقابلہ میں وہ صنعت کبھی بھی اتنی ترقی نہیں کر سکے گی جو سارے ملک میں
ایک ہی نظام کے ماتحت مقابلہ اور مسابقت کے بغیر جاری ہے.اور اس طرح ملک کا
قدم علمی اور صنعتی میدان میں ترقی کی بجائے آہستہ آہستہ تنزل کی طرف پڑنا شروع
ہو جائے گا.بیشک بعض خاص خاص صنعتیں حکومت کے ہاتھ میں رکھی جاسکتی ہیں اور
رکھنی چاہئیں مگر اس اصول کو کھلی صورت میں ساری صنعتوں پر جاری کرنا ملک وقوم کی
تباہی کا بیج بونا ہے.3.اوپر کی دونوں باتوں کالازمی نتیجہ یہ بھی ہوگا کہ اس قسم کے اشتراکی نظام میں قوم
کی دماغی ترقی اور ذہنی نشو ونما کی رفتار آہستہ آہستہ دھیمی ہونی شروع ہو جائے گی اور
بالآخر انسانی دماغ ایک ترقی کرنے والی اور بڑھنے والی چیز کی بجائے محض مشین ہو کر رہ
جائے گا.-4 کمیونزم کے نظام میں انفرادی ہمدردی اور مواسات کے جذبات کو بھی کچلا گیا
ہے کیونکہ جس صورت میں کہ غرباء اور مستحقین کی اعانت صرف حکومت کے ہاتھ میں
244
Page 245
ہوگی اور نہ ہی کسی کے پاس کوئی ایسا فالتو روپیہ ہو گا جس سے وہ کسی مستحق کی امداد کر سکے
یا کسی عزیز کو تحفہ ہی دے سکے تو لازماً انسانیت کے وہ اعلیٰ اخلاق جو محبت و موالات اور
ہمدردی اور قربانی اور مہمانوازی اور غریب پروری اور صلہ رحمی اور خدمت ہمسایہ کے
ساتھ تعلق رکھتے ہیں، آہستہ آہستہ مرنے شروع ہو جائیں گے اور انسانی سوسائٹی بھی
اسی طرح میکا نائزڈ (Mechanised) ہو جائے گی یعنی مشین بن جائے گی جس
طرح آجکل مغربی ممالک میں ہر چیز اور ہر عمل کو مشین کی صورت میں ڈھالا جارہا ہے.5.کمیونزم کے نظام میں یہ نقص بھی ہے کہ اس میں انسانی دماغ کی ارفع طاقتوں
کی کوئی زائد قیمت نہیں لگائی گئی اور اُسے بھی اسی لیول یعنی سطح پر رکھا گیا ہے جس پر کہ
ہاتھ پاؤں کی عام محنت اور مزدوری کو رکھا گیا ہے.اور ایسے نظام کا آخری نتیجہ قوم کے
ذہنی دیوالیہ پن کے سوا اور کچھ نہیں ہوسکتا، لیکن چونکہ ایسے نتیجے کچھ عرصہ کے بعد نکلا
کرتے ہیں اس لئے موجودہ جوش و خروش میں یہ تمام خطرات نظر انداز کئے جارہے ہیں
وغیرہ وغیرہ.بہر حال اشتراکیت کا نظام روس کے قدیم ظالمانہ نظام کا ایک طبعی رد عمل ہے.مگر یہ رد عمل اعتدال کی صورت میں ظاہر ہونے کی بجائے دوسری انتہا کی صورت میں
ظاہر ہوا ہے اور عملی نتیجہ یہ ہے کہ قوم کو ایک گڑھے (سرمایہ داری ) سے نکال کر دوسرے
گڑھے(اشتراکیت) میں دھکیلا جا رہا ہے.اسلام میں دولت کی منصفانہ تقسیم کا انتظام
اشتراکیت کے مقابل پر اسلام نے جو صحیح فطرت کا مذہب ہے اور خود
خالق فطرت کا بھیجا ہوا ہے اپنی حکیمانہ شریعت میں دونوں طرف کی انتہا سے بچتے
ہوئے کامل اعتدال اور میانہ روی کی تعلیم دی ہے.وہ ایک طرف تو کمیونزم کی طرح
245
Page 246
انسان کو انفرادی جد و جہد کے سب سے بڑے فطری محرک یعنی اپنی ذاتی محنت کے پھل
کھانے کے حق سے محروم کرتا ہے اور نہ ہی دوسری طرف سرمایہ داری کی طرح ملک و قوم
کی دولت کے چند ہاتھوں میں جمع ہونے یا ایک خاص طبقہ کی اجارہ داری بنے کا راستہ
کھولتا ہے.اور اس کے لئے اسلام نے بعض نہایت حکیمانہ بنیادی احکام جاری کئے
ہیں جو چند مختصر فقروں کی صورت میں درج ذیل کئے جاتے ہیں :.اول اسلام نے تقسیم ورثہ کا ایسا قانون بنایا ہے کہ اس پر عمل کرنے کے نتیجہ میں
ملک کی دولت خود بخود منصفانہ رنگ میں تقسیم ہوتی رہتی ہے.کیونکہ اسلام نے صرف
بڑے لڑکے یا صرف نرینہ اولاد کو ہی وارث قرار نہیں دیا بلکہ ساری اولاد کے لئے خواہ وہ
لڑکے ہوں یا لڑکیاں ورثہ میں حصہ رکھا ہے اور اولاد کے علاوہ بیوی اور خاوند اور ماں اور
باپ اور بعض صورتوں میں بہن اور بھائی اور دوسرے قریبی عزیزوں کو بھی محروم نہیں
کیا.اور یہ عمل ایسا ہے کہ اس کے نتیجہ میں ملک کی دولت طبعی طور پر مصنفانہ رنگ میں
تقسیم ہوتی رہتی ہے اور چند ہاتھوں میں جمع نہیں ہوسکتی.دوسرے اسلام نے سود لینے اور دینے کو حرام قرار دیا ہے اور چونکہ سود اپنی
دوسری خرابیوں کے علاوہ دولت کی ناواجب تقسیم کا ایک بھاری ذریعہ ہے اس لئے اس
حرمت کے نتیجہ میں بھی ملکی دولت کے چند ہاتھوں میں جمع ہونے کا رستہ خود بخود بند
ہو جاتا ہے.بیشک موجودہ زمانہ میں سود کا جال وسیع ہو جانے کی وجہ سے بظاہر یہ نظر آتا
ہے کہ شاید سود کے بغیر گزارہ نہیں چل سکتا مگر یہ صرف نظر کا دھوکا ہے جو موجودہ ماحول کی
وجہ سے پیدا ہو ا ہے ورنہ جب مسلمان نصف دنیا سے زائد حصہ پر حکمران تھے اس وقت
سود کے بغیر ہی ساری تجارتیں چلتی تھیں اور انشاء اللہ آئندہ پھر چلیں گی.تیسرے اسلام نے جوئے کو بھی حرام قرار دیا ہے کیونکہ اس لغو عادت کے ذریعہ
بھی دولت کی ناواجب تقسیم کا رستہ گھلتا ہے اور محنت اور کوشش اور ہنر کے ذریعہ روزی
246
Page 247
کمانے کی بجائے وقت کو بے ہودہ طور پر ضائع کرنے اور محض اتفاق پر اپنی آمد کی بنیاد
رکھنے کی عادت پیدا ہوتی ہے.چوتھے اسلام نے مال و دولت کو خزانوں کی صورت میں جمع کر کے رکھنے سے بھی روکا
ہے تا کہ یہی اموال ملکی صنعت و تجارت میں لگ کر بیکاروں کی روز گار کا ذریعہ بن سکے.پانچویں اسلام نے ہر مالدار کی دولت پر زکوۃ کی صورت میں بھاری ٹیکس لگایا
ہے اور حکم دیا ہے کہ جو ز کوۃ کا مال وصول ہو وہ نہ صرف غریبوں اور محتاجوں وغیرہ میں
تقسیم کیا جائے بلکہ ایسے بیکار لوگوں کی امداد میں بھی خرچ کیا جائے جو کوئی ہنر تو رکھتے
ہیں مگر اس ہنر سے فائدہ اُٹھانے کے ذرائع نہیں رکھتے.اور اسلام نے زکوۃ کے نظام
کی غرض و غایت یہ بیان کی ہے کہ:.تُوْخَذُ مِنْ أَغْنِيَاءِ هِمْ وَتُرَدُّ إِلَى فُقَرَاءِ هِمْ.(بخاری کتاب الزکوة )
یعنی ” زکوۃ کا صحیح مصرف یہ ہے کہ امیروں کی دولت کو کاٹ کر اُسے غریبوں اور
محتاجوں میں پھیلایا جائے.اسی طرح وہ دفینے جو پرائیویٹ جگہوں میں سے برآمد ہوں اُن پر بھی اسلام
نے ہیں فیصدی کا بھاری ٹیکس لگا کر غریبوں کی امداد کا رستہ کھولا ہے.چھٹے اسلام نے زکوۃ کے جبری ٹیکس کے علاوہ مسلمانوں کو تاکیدی احکام دیئے
ہیں کہ وہ اپنے مالوں میں سے غریبوں کی امداد کے لئے عام صدقہ بھی نکالا کریں تا کہ
زکوۃ کے علاوہ جو حکومت کے ذریعہ وصول ہو کر تقسیم ہوتی ہے لوگوں کو خود انفرادی طور پر
بھی اپنے غریب بھائیوں اور ہمسایوں کی امداد کا احساس رہے اور آپس میں اخوت اور
تعاون اور مواسات کی رُوح ترقی کرے.ساتویں بالآخر اسلام نے حکم دیا ہے کہ اگر اوپر کے بیان کردہ ذرائع کے نتیجہ میں
تمام غرباء کی خاطر خواہ امداد کا انتظام نہ ہو سکے تو اس صورت میں حکومت کا فرض ہے کہ
247
Page 248
خود اپنے خزانوں سے محتاجوں کی امداد کا انتظام کرے تا کہ ہرفرد کو اس کی بنیادی
ضروریات کی چیزیں لازماً پہنچتی رہیں.پیہ وہ سات اصولی طریق ہیں جن کے ذریعہ اسلام نے دُنیا میں دولت کی
منصفانہ تقسیم اور غریبوں اور محتاجوں کی امداد کا انتظام کیا ہے ( اسلام اور اشتراکیت کی
تفصیلی بحث کے لئے حضرت خلیفة المسیح الثانی رضی اللہ عنہ کی تصنیف ” اسلام
کا اقتصادی نظام اور خاکسار کے رسالہ ” اشتراکیت اور اسلام کا مطالعہ فرمائیں).اور ظاہر ہے کہ اگر ایک طرف افراد کے لئے اپنی ذاتی جدوجہد کے ثمرہ سے فائدہ
اُٹھانے کا راستہ کھلا رہے اور انسان کی دماغی طاقتیں اس فطری محرک اور جائز مقابلہ اور
مسابقت کے مواقع سے محروم ہو کر منجمد ہونے سے محفوظ رہیں اور دوسری طرف ملک
میں دولت کی منصفانہ تقسیم کا نظام بھی قائم ہو اور ملک کی دولت کو سموتے رہنے کا طریق
مسلسل جاری رکھا جائے تو یہ ایک نہایت ہی اعلیٰ اعتدال کا رستہ ہوگا جو دونوں طرف
(یعنی سرمایہ داری اور اشتراکیت) کی خرابیوں سے بچتے ہوئے دونوں طرف کی خوبیوں
کو اپنے اندر جمع کرلے گا اور یہی وہ سنہری رستہ ہے جو اسلام نے اختیار کیا ہے.خلاصہ کلام یہ کہ روس کی اشتراکیت کو اپنے بنیادی اُصولوں کے لحاظ سے
دہریت کے ساتھ کوئی براہ راست تعلق نہیں ہے بلکہ یہ ایک محض اقتصادی نظام ہے
جس نے صرف اپنی مضبوطی کے لئے موجود مذاہب کی تعلیم پر بالواسطہ حملہ کیا ہے.مگر
جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں یہ حملہ صرف ایک کو رانہ رد عمل کی حیثیت رکھتا ہے جو لوگوں کو ایک
انتہا سے ہٹا کر دوسری انتہا کی طرف لے جا رہا ہے اور اس رد عمل میں ہی اس کی آخری
تباہی کا بیج مخفی ہے.لیکن اس کے مقابل پر جوتعلیم اسلام نے دی ہے وہ پورے پورے
اعتدال اور حق و انصاف کی تعلیم ہے اور یقیناً جب روس اپنے موجودہ رد عمل کے خمار
سے جاگے گا تو اُسے اسلام کے فطری مذہب کے سوا اور کوئی امن کی جگہ نہیں ملے گی.248
Page 249
خاتمہ
اب میں اس حصہ مضمون کو ختم کرتا ہوں جو ہستی باری تعالیٰ کے متعلق عقلی دلائل
کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور جیسا کہ میں نے شروع مضمون میں بیان کیا تھا آخر میں پھر
عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ میں نے اس مضمون میں بار یک علمی بحثوں سے احتراز کیا ہے
اور صرف موٹی موٹی باتوں کو کسی قدر تصریح کے ساتھ بیان کر دیا ہے اور دراصل میرے
مخاطب بھی زیادہ تر نوجوان طبقہ کے لوگ ہیں جو بوجہ طبیعت کی خامی کے بعض اوقات
جدید تعلیم سے غلط طور پر متاثر ہوکر محمد انہ خیالات قائم کر لیتے ہیں.مگر میں سمجھتا ہوں کہ
جو کچھ میں نے لکھا ہے وہ ایک صاف دل انسان کے لئے کافی ہے.اور اگر کسی شخص
کے دل میں اس مضمون کے پڑھنے کے بعد بھی کوئی شبہ رہے تو میں امید کرتا ہوں کہ وہ
ان اصولی باتوں کی روشنی میں حل کیا جا سکے گا جو میں نے اس جگہ بیان کی ہیں.باقی
ایسے شخص کا علاج میرے پاس
کوئی نہیں ہے اور نہ کسی اور شخص کے پاس ہے جو خواہ مخواہ
کجروی کا طریق اختیار کر کے اپنے آپ کو شبہات کے بھنور سے نکالنا نہیں چاہتا یا جو
اپنی آنکھوں پر تعصب کی پٹی باندھے رکھ کر حق و صداقت کو دیکھنے اور شناخت کرنے کے
پر
لئے تیار نہیں.ایسے لوگوں کا علاج صرف خدا کے پاس ہے اور میں دعا کرتا ہوں کہ وہ
اُن کے دل کی کجی کو دُور کرے اور اُن کی آنکھوں کی پٹی اتارے اور اپنے فضل خاص
سے ایسا انتظام فرمائے کہ اس کا کوئی بندہ بھی ایسی حالت میں دُنیا سے رخصت نہ ہو کہ وہ
اپنے خالق و مالک کو نہ پہنچا تا ہو.کیونکہ اس سے بڑھ کر انسان کے لئے کوئی بدقسمتی اور
محرومی نہیں کہ وہ اپنے پیدا کرنے والے اور اپنی زندگی کے سہارے اور اپنی ساری
طاقتوں کے منبع و ماخذ کی شناخت کے بغیر دُنیا سے رخصت ہو جائے.حضرت مسیح موعود علیہ السلام بانی سلسلہ احمدیہ کی ایک پیاری تحریر پر اس مضمون
کو ختم کرتا ہوں.آپ فرماتے ہیں:
249
Page 250
کیا بد بخت وہ انسان ہے جس کو اب تک یہ پتہ نہیں کہ اُس کا ایک خُدا
ہے جو ہر چیز پر قادر ہے.ہمارا بہشت ہے.ہماری اعلیٰ
لذات ہمارے خدا میں ہیں کیونکہ ہم نے اُس کو دیکھا اور ہر ایک
خوبصورتی اُس میں پائی.یہ دولت لینے کے لائق ہے اگر چہ جان دینے
سے ملے.اور یہ عمل خریدنے کے لائق ہے اگر چہ تمام وجود کھونے سے
حاصل ہو.اے محرومو! اس چشمہ کی طرف دوڑو کہ وہ تمہیں سیراب
کرے گا.یہ زندگی کا چشمہ ہے جو تمہیں بچائے گا.میں کیا کروں اور
کس طرح یہ خوشخبری دلوں میں بٹھا دوں اور کس دف سے میں
بازاروں میں منادی کروں کہ تمہارا یہ خُدا ہے تا لوگ سُن لیں اور کس
روا سے علاج کروں تا سننے کے لئے لوگوں کے کان کھلیں“.(کشتی نوح)
مه
اب میں خدا کے فضل سے ہستی باری تعالیٰ کے متعلق عقلی دلائل کی بحث ختم
کر چکا ہوں مگر جیسا کہ میں نے اس مضمون کے شروع میں ہی بتادیا تھا یہ دلائل انسان کو
صرف اس ایمان تک لے جاتے ہیں کہ اس کا رخانہ عالم کا ضرور کوئی خالق و مالک ہونا
چاہئے.لیکن ظاہر ہے کہ یہ ہونا چاہئے والا ایمان خواہ وہ کتنا ہی پختہ اور روشن ہو بہر حال
اس ایمان سے کمزور اور فروتر ہے کہ اس دنیا کا واقعی ایک خالق و مالک خدا ہے.کیونکہ
جہاں” ہونا چاہئے “ والا ایمان صرف ایک پختہ قیاس اور واضح اشارے کی حیثیت رکھتا
ہے وہاں ” ہے“ والے ایمان کو متعین مشاہدہ کا درجہ حاصل ہے جس کے بعد انسان گویا
خدا کو عملاً دیکھ لیتا ہے اور کسی امکانی شک وشبہ کی گنجائش بھی باقی نہیں رہتی.سواس
مؤخر الذکر یقین کے دلائل انشاء اللہ کتاب کے دوسرے حصہ میں بیان کئے جائیں
و,
250
Page 251
گے.جہاں یہ بتایا جائے گا کہ کس طرح خدا تعالیٰ اپنے مخفی اور وراء الوراء وجود کو اپنے
انبیاء اور اولیاء کے ذریعہ دُنیا پر ظاہر فرماتا ہے اور کس طرح یہ خُدارسیدہ بندے اس کے
از لی علم وقدرت کے یقینی کرشمے دکھا دکھا کر اس کی ہستی کولوگوں کی نظروں کے اس قدر
قریب لے آتے ہیں کہ گویا خدا زمین پر نازل ہو کر اپنے بندوں کے سامنے آکھڑا ہوتا
ہے.یہ وہی نظارہ ہے جو حضرت آدم نے اپنے وقت میں اور حضرت نوح نے اپنے
وقت میں اور حضرت ابراہیم نے اپنے وقت میں اور حضرت موسیٰ نے اپنے وقت میں
اور حضرت عیسلے نے اپنے وقت میں اور حضرت محمد مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم (فدا نفسی)
نے اپنے وقت میں لوگوں کو دکھایا اور آج حضرت مسیح موعود علیہ السلام بانی سلسلہ احمدیہ
اپنے وقت میں لوگوں کو دکھا رہے ہیں.چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت اور غلامی میں دنیا کو مخاطب کر کے فرمایا:.آؤ! میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ خدا ہے اور وہ علیم ہے کیونکہ میں ایک
انسان ہونے کی وجہ سے علم کامل نہیں رکھتا لیکن خدا مجھے کہتا ہے کہ یہ چیز
یوں ظاہر ہوگی اور پھر باوجود ہزاروں پردوں کے پیچھے مستور ہونے کے
بالآخر وہ چیز اسی طرح ظاہر ہوتی ہے جس طرح خدا نے کہا تھا.آؤ اور
اس کا امتحان کر لو.میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ خُدا ہے اور وہ قدیر ہے.کیونکہ میں بوجہ بشر ہونے کے قدرت کاملہ نہیں رکھتا لیکن خدا مجھے کہتا
ہے کہ میں فلاں کام اس اس طرح پر کروں گا.اور وہ کام انسانی طاقت
سے اس طرح پر نہیں ہو سکتا اور اس کے رستہ میں ہزاروں روکیں حائل
ہوتی ہیں مگر پھر بھی وہ اسی طرح ہو جاتا ہے جس طرح خدا فرماتا ہے.آؤ اور اس کا امتحان کر لو.میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ خدا ہے اور وہ سمیع
ہے اور اپنے بندوں کی دُعاؤں کو سنتا ہے.کیونکہ میں خدا سے ایسے
251
Page 252
مكم
کاموں کے متعلق دُعا مانگتا ہوں جو ظاہر میں بالکل انہو نے نظر آتے
ہیں مگر خدا میری دُعا سے ان کاموں کو پورا کر دیتا ہے.آؤ اور اس کا
امتحان کر لو.میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ خدا ہے اور وہ نصیر ہے کیونکہ جب
اس کے نیک بندے چاروں طرف سے مصائب اور عداوت کی آگ
میں گھر جاتے ہیں تو وہ اپنی نصرت سے خود اُن کے لئے مخلصی کا رستہ
کھولتا ہے.آؤ اور اس کا امتحان کر لو.میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ خدا ہے
اور وہ خالق ہے کیونکہ میں بوجہ بشر ہونے کے خلق کی طاقت نہیں رکھتا
مگر وہ میرے ذریعہ اپنی خالقیت کے جلوے دکھاتا ہے جیسا کہ اس نے
بغیر کسی مادہ کے اور بغیر کسی آلہ کے میرے گرتے پر اپنی روشنائی کے
چھینٹے ڈالے.آؤ اور اس کا امتحان کر لو.میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ خدا
ہے اور وہ مسلم ہے اور اپنے خاص بندوں سے محبت اور شفقت کا کلام
کرتا ہے جیسا کہ اُس نے مجھ سے کیا.آؤ اور اس کا امتحان کر لو.میں
تمہیں دکھاتا ہوں کہ خدا ہے اور وہ رب العالمین ہے اور کوئی چیز اس کی
ربوبیت سے باہر نہیں.کیونکہ جب وہ کسی چیز کی ربوبیت کو چھوڑتا ہے تو
پھر وہ چیز خواہ وہ کوئی ہو قائم نہیں رہ سکتی.آؤ اور اس کا امتحان کرلو.پھر
میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ خُدا ہے اور وہ مالک ہے.کیونکہ مخلوقات میں
سے کوئی چیز اس کی حکم عدولی نہیں کر سکتی.اور وہ جس چیز پر جو تصرف
بھی کرنا چاہے کر سکتا ہے.پس آؤ کہ میں تمہیں آسمان پر اس کے
تصرفات دکھاؤں اور آؤ کہ میں تمہیں زمین پر اس کے تصرفات
دکھاؤں اور آؤ کہ میں تمہیں ہوا پر اس کے تصرفات دکھاؤں اور آؤ کہ
میں تمہیں پانیوں پر اُس کے تصرفات دکھاؤں اور آؤ کہ میں تمہیں
252
Page 253
پہاڑوں پر اُس کے تصرفات دکھاؤں اور آؤ کہ میں تمہیں قوموں پر اُس
کے تصرفات دکھاؤں.اور آؤ کہ میں تمہیں حکومتوں پر اس کے تصرفات
دکھاؤں اور آؤ کہ میں تمہیں دلوں پر اس کے تصرفات دکھاؤں.پس آؤ
اور امتحان کرلو.(ماخوذ از متفرق کتب حضرت مسیح موعود علیہ السلام بانی سلسلہ احمدیہ )
یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے، لیکن سوچو کہ اگر یہ دعویٰ ثابت ہو جائے تو کیا
دہریت قائم رہ سکتی ہے؟ مگر مجھے اسی ذات
کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے
اور جس کے سامنے میں نے ایک دن مر کر کھڑا ہونا ہے کہ جیسا کہ میں انشاء اللہ کتاب
کے دوسرے حصہ میں تفصیل کے ساتھ ثابت کرونگا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے
سُنت اللہ کے مطابق یہ سب باتیں کر کے دکھا دیں اور آپ کی زبان پر خدا کی طرف
سے جاری کی ہوئی باتیں اب بھی اس طرح پوری ہو رہی ہیں جس طرح کہ ایک زور دار
بارش کے قطرے آسمان سے گرتے ہوئے نظر آتے ہیں.اور کئی باتیں آئندہ پوری
ہونے والی ہیں.مثلاً اپنے خداداد مشن کی ترقی کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام
بڑی تحدی کے ساتھ فرماتے ہیں:
”اے تمام لوگو! سن رکھو کہ یہ اس کی پیشگوئی ہے جس نے زمین و آسمان
بنایا.وہ اپنی اس جماعت کو تمام ملکوں میں پھیلا دے گا اور حجت اور
برہان کی رُو سے سب پر اُن کو غلبہ بخشے گا.وہ دن آتے ہیں بلکہ قریب
ہیں کہ دُنیا میں صرف یہی ایک مذہب ہوگا جو عزت کے ساتھ یاد کیا
جائے گا.خدا اس مذہب اور اس سلسلہ میں نہایت درجہ اور
فوق العادت برکت ڈالے گا.اور ہر ایک کو جو اس کے معدوم کرنے کا
فکر رکھتا ہے نامر اور کھے گا اور یہ غلبہ ہمیشہ رہے گا یہاں تک کہ قیامت
تفصیل کے لئے دیکھو حضرت
مسیح موعود کی تصنیف ”حقیقۃ الوی اور نزول مسیح ، وغیرہ
253
Page 254
آجائے گی...میں تو ایک تخم ریزی کرنے آیا ہوں.سو میرے ہاتھ
سے وہ تخم بویا گیا.اور اب وہ بڑھے گا اور پھولے گا اور کوئی نہیں جو اس
کو روک سکے.‘ ( تذکرۃ الشہادتین صفحہ 64 و65)
پھر فرماتے ہیں:
وو
” خدا تعالیٰ نے مجھے بار بار خبر دی ہے کہ وہ مجھے بہت عظمت دے گا اور
میری محبت دلوں میں بٹھائے گا.اور میرے سلسلہ کو تمام دُنیا میں
پھیلائے گا اور سب فرقوں پر میرے فرقہ کو غالب کرے گا.اور میرے
فرقہ کے لوگ اس قدر علم و معرفت میں کمال حاصل کریں گے کہ اپنی
سچائی کے نو ر اور اپنے دلائل اور نشانوں کی رُو سے سب کامنہ بند کر دیں
گے.اور ہر ایک قوم اس چشمہ سے پانی پیئے گی.اور یہ سلسلہ زور سے
بڑھے گا اور پھولے گا یہاں تک کہ زمین پر محیط ہو جاوے گا....اور خدا
نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ میں تجھے برکت پر برکت ڈونگا یہاں
تک کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے.سواے سُننے
والو! ان باتوں کو یا درکھو اور ان پیش خبریوں کو اپنے صندوقوں میں محفوظ
رکھ لو کہ یہ خدا کا کلام ہے جو ایک دن پورا ہوگا“.اور اسلام کی عالمگیر ترقی کے متعلق جس کی خدمت کے لئے آپ مبعوث ہوئے
تھے فرماتے ہیں:
اب وہ دن نزدیک آتے ہیں کہ جو سچائی کا آفتاب مغرب کی طرف
سے چڑھے گا اور یورپ کو کچے خدا کا پتہ لگے گا.قریب ہے کہ سب
ملتیں ہلاک ہونگی مگر اسلام.اور سب حربے ٹوٹ جائیں گے مگر اسلام کا
تجلیات الہیہ صفحہ 18-17 - روحانی خزائن جلد نمبر 20 مطبوعہ انگلستان 1984ء
254
Page 255
آسمانی حربہ کہ وہ نہ ٹوٹے گا نہ گند ہو گا جب تک دجالیت کو پاش پاش نہ
کر دے.وہ وقت قریب ہے کہ خدا کی سچی توحید جس کو بیابانوں کے
رہنے والے اور تمام تعلیموں سے غافل بھی اپنے اندر محسوس کرتے ہیں
ملکوں میں پھیلے گی.اُس دن نہ کوئی مصنوعی کفارہ باقی رہے گا اور نہ کوئی
مصنوعی خدا.اور خدا کا ایک ہی ہاتھ کفر کی سب تدبیروں کو باطل کر دے
گا لیکن نہ کسی تلوار سے اور نہ بندوق سے بلکہ مستعد روحوں کو روشنی عطا
کرنے سے اور پاک دلوں پر ایک نو را تارنے سے.تب یہ باتیں جو
میں کہتا ہوں سمجھ میں آئیں گی“.(تذکرہ صفحہ 285 286)
کیا جماعت احمدیہ کی موجودہ حالت جو آج دنیا کے وسیع میدان میں ایک رینگتی
ہوئی چیونٹی سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی اور کیا مسلمانوں کی موجودہ کمزوری کہ وہ غیر مسلم
طاقتوں کے مقابل پر گویا ایک بیمار انسان“ کے طور پر سمجھے جاتے ہیں اس عظیم الشان
مستقبل کی کوئی امید پیدا کرتی ہے؟ اگر نہیں اور ہرگز نہیں تو پھر اگر یہ سب کچھ اسی طرح
وقوع میں آگیا جس طرح کہ اس پیشگوئی میں بتایا گیا ہے تو کیا یہ ثابت نہ ہوگا کہ اس
دنیا کے اوپر ایک علیم وقدیر خُدا ہے جو اپنے طاقتور ہاتھوں میں قضاء وقدر کی تاروں کو
اس طرح تھامے ہوئے ہے جس طرح ایک شاہسوار اس گھوڑے کی باگوں کو تھامتا ہے
جسے اُس نے کسی خاص منزل تک پہنچانا ہو.بس اب میں اپنے ناظرین سے رُخصت
ہوتا ہوں اور سلامتی ہو ان پر جو خدا کی بھیجی ہوئی ہدایت کو قبول کرتے ہیں.وَاخِرُ دَعُونَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ
خداوند عالم کا ایک عاجز بندہ
خاکسار
مرزا بشیر احمد آف قادیان
255