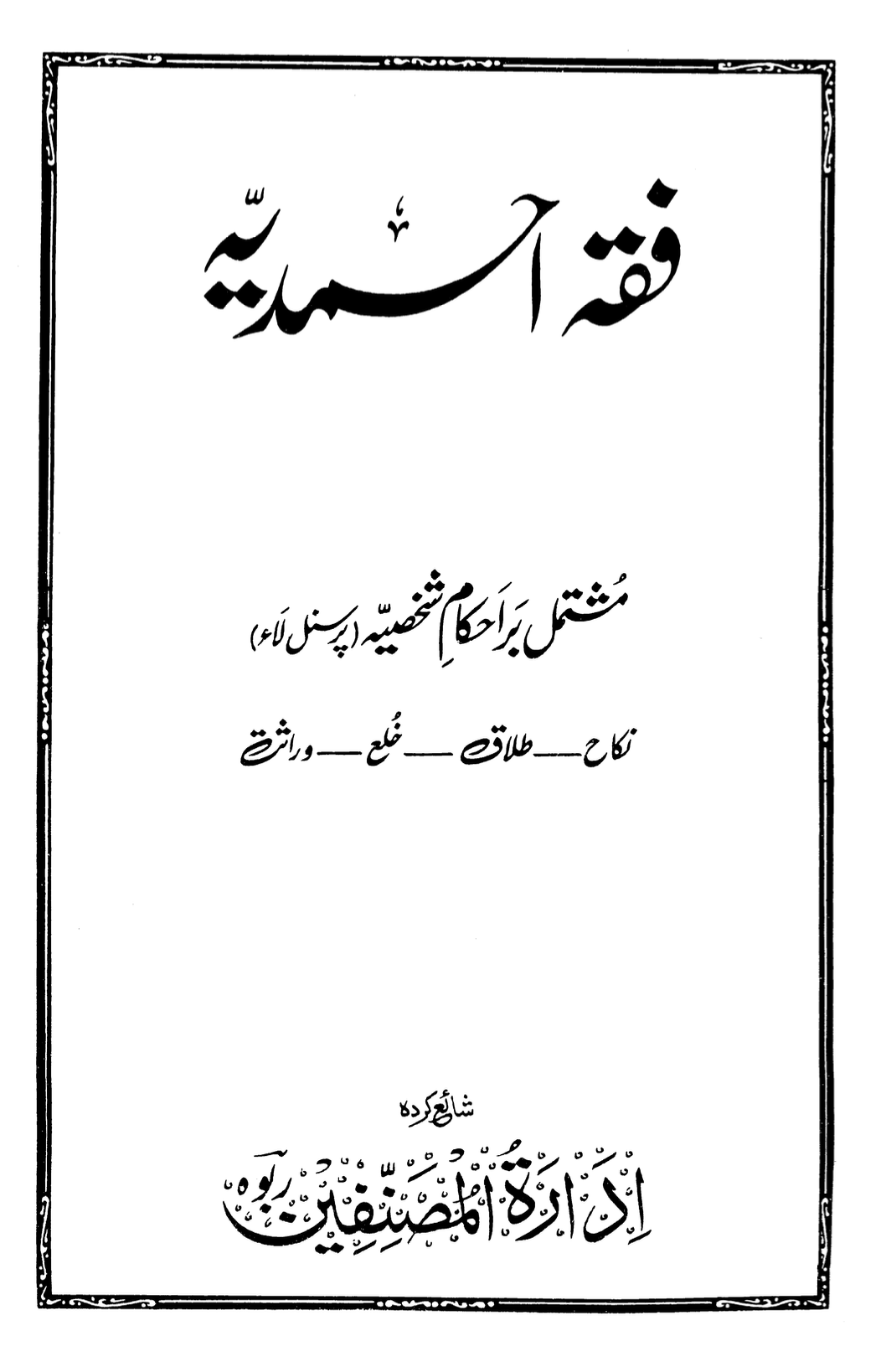Complete Text of FiqahAhmadiyya Part2
Content sourced fromAlislam.org
Page 1
فقة المادية
مشتمل بر احکام شخصی پرسنل کادر)
لاء)
نکاح طلاق خلع وراثة
إدارة المصنفين
Page 2
ضروری ہدایت
عنوان
پیش لفظ ایڈیشن اول
پیش لفظ ایڈیشن دوم
فقہ احمدیہ کے ماخذ
استدراک
تعریف نکاح
فرست
q
عنوان
دو گواہوں کا ہونا
۱۵ مهر مثل
۱۶ مہر کی مقدار
نکاح اپنے انعقاد اور اثرات کے اعتبار
صفح
۴۲
۴۳
۴۵
۵۰
۵۱
۵۲
"
مقاصد نکاح
الميت نكاح
بلوغت
19 سے صحیح ہوتا ہے یا فاسد یا باطل -
رضا
کفائت
انعقاد نكاح
صحت نکاح اور اس کی شرائط
موانع نکاح
ابدی محرمات بر بنائے نسب
ابدی محرمات بر بنائے مصاہرت
۲۰ نکاح صحیح
۲۱ فریقین کے حقوق و فرائض
بیوی کے حقوق و فرائض
۲۳ خاوند کے حقوق و فرائض
۲۶ نکاح فاسد
نکاح باطل
۲۷ تعدد ازدواج
۲۹ ولادت اور نسب
ابدی محرمات بر بنائے رضاعت ۳۳ اقل مدت حمل
لعان
وقتی محرمات
استحقاق ولایت نکاح
۳۵ انکار نسب
"
۴۱
لاوارث بچے کی پرورش
۵۳
۵۴
۵۶
۵۸
4.۲۴
۶۵
YA
ง
Page 3
عنوان
طلاق
نشوز اور اس کی اصلاحی تدابیر
شرائط صحت طلاق
طلاق رجعی
طلاق بائن
طلاق بتہ
ضلع کے فیصلہ کے لئے قاضی کا اطمینان
خلع کی صورت میں حق مہر
خیار بلوغ
خیار بلوغ اور قاضی کا فیصلہ
خیار بلوغ کا استعمال
فسخ نکاح
صفحه
ا حضانت
"
۷۲
مدت حضانت
عنوان
صفحہ
استحقاق حضانت
اہمیت حضانت
۷۵ دوران حضانت نان و نفقه
حدود حضانت
۸۴
AL
AA
سقوط حضانت
خیار التميز
مسائل وراثت
مالح میراث
٩٠ ذوى الفروض
۹۳ عصات
۹۴ ذوی الفروض کے حصے
۹۶ ذوی الارحام
1.9
+11
IFF
۱۱۲
۱۱۵
114
A
۱۲۱
"
۱۲۳
۱۲۶
۱۲۸
۱۲۹
"
۱۳
مفقود الخبر
۹۷ ذوی الارحام کے درجے
ابلاء وظهار
۹۸ ارد
مریضہ بیوی
99 حول
عدت
حمل کی میراث
نان و نفقه
حادثات
نان و تفقه بصورت طلاق
۱۰۶ مفقود الخبر
بیوہ عدت وفات اور اس کے بعد ایک سال ولد الملاعنة
تک خاوند کے مکان میں رہائش رکھ سکتی یتیم پوتے یا نواسے کی میراث
ہے.ماں باپ کا نفقہ
1.2
I-A
Page 4
ضروری ہدایت
شریعت کے جو مسائل نہیں قرآنی یا سنت نبوت پر مبنی ہیں اور
انہیں تو اتر عملی کی حیثیت حاصل ہے وہ دائمی ہیں باقی مسائل
ائمہ دین اور فقہائے اسلام کے اجتہاد پر مبنی ہیں.ایسے اجتہادی مسائل
میں مقررہ ضابطہ کے تحتے سلسلہ کے اہل الرائے علماء کے مشورہ اور خلیفہ وقرتے
کی منظوری سے تبدیلی ہو سکتی ہے.ووسلم فاکر
هذا الاحد
خليفة أسبع الرابع
10-2.83
Page 5
بسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ نَحْمَدُهُ وَتُصَلَّى عَلَى رَسُولِهِ الكريم
پیش لفظ
ایڈیشن.اول.قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے یہ اس کی آخری اور کامل کتاب ہے اور اس میں ہماری
ساری دینی، اخلاقی اور روحانی ضرورتوں کو اصولاً و اجمالاً پورا کیا گیا ہے قیامت تک بنی نوع انسان کو
جو بھی مسائل درپیش ہو سکتے ہیں ان کا حل قرآن کریم میں موجود ہے.جس طرح قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لئے انسانوں کی مکمل ہدایت اور رہنمائی کی
غرض سے نازل فرمایا ہے اسی طرح اس ہدایت کی تعلیم دینے، اس پر عمل پیرا ہونے اور اس کی حکمتیں
بیان فرمانے کے لئے قیامت تک کے لئے حضرت محمد مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ کامل بنا کر مبعوث
فرمایا اور قرآن کریم کے معارف اور اس کی حکمتیں آپ کے قلب مطر پر روش فرمائیں چنانچہ خود قرآن کریم
کے ارشاد کے مطابق انسانی زندگی کو عمل کے جس سانچہ میں ڈھلنا چاہئیے اس کی اکمل اور احسن تصویر حضرت
محمد مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار میں موجود ہے جس کی تقلید امت محمدیہ کے لئے قیامت تک واجب
قرار دے دی گئی ہے.اس مضمون کو بیان کرتے ہوئے قرآن کریم فرماتا ہے :-
لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ له
تمہارے لئے یعنی ان لوگوں کے لئے جو اللہ اور اخروی دن سے ملنے کی امید رکھتے ہیں اور
اللہ کا بہت ذکر کرتے ہیں اللہ کے رسول میں ایک اعلیٰ نمونہ ہے جس کی انہیں پیروی کرنی
چاہئیے.پھر فرمایا :-
نے سورۃ الاحزاب آیت ۲۲
Page 6
قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ الله فَاتَّبِعُونِي يُجيبُكُمُ الله
کہ کہ اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تومیری اتباع کرو اس صورت میں وہ بھی
تم سے محبت کرے گا.ایک اور موقع پر فرمایا :-
مَا الكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا له
رسول جو کچھ تم کو دے اس کو لے لو اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ.معاملات شریعت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کا ہی دوسرا نام سنت رسول" ہے جو
قرآن
کریم پر عمل پیرا ہونے کا طریق متعین کرتی ہے.اصولِ فقہ میں اسے قرآن کریم کے بعد دوسری حیثیت
حاصل ہے.آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عملی نمونہ کے بعد آپ کے ان ارشادات کا مقام ہے جو روایات کی
شکل میں ہم تک پہنچے اور جنہیں حدیث کا اصطلاحی نام دیا گیا.یہ ارشادات تعلیم کتاب اور بیان حکمت کے
مضمون سے تعلق رکھتے ہیں.اس بارہ میں قرآن کریم میں آپ کی بعثت کے مقاصد بیان کرتے ہوئے آپ کے متعلق بتایا گیا :-
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَب وَالْحِكْمَةَ
اور انہیں کتاب اور حکمت سکھائے.پس یہ تعلیم کتاب اور بیان حکمت کا وہ پہلو ہے جو فرمودات نبوئی سے تعلق رکھتا ہے اور فقہی اصطلاح
میں اسے ہی حدیث کہا گیا ہے.خود قرآن کریم کی واضح ہدایت سے پتہ چلتا ہے کہ امور دینیہ میں جو قول بھی
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو اس کی بنیا د لازما وحی الہی میں موجود ہے.چنانچہ فرمایا.وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى هُ إِنْ هُوَ إِلَّا وَى يولى
اور وہ اپنی خواہش نفسانی سے کلام نہیں کرتا بلکہ وہ یعنی اس کا پیش کردہ کلام صرف خدا
کی طرف سے نازل ہونے والی وحی ہے.یعنی آپ کا کوئی قول بھی نفسی خواہشات کے تابع نہیں بلکہ ہر بات وحی الہی پر مبنی ہے اس حیثیت
له سورة آل عمران آیت ۳۲
له سورة الحشر آیت ۸
ے.سورة البقره آیت ۱۳۰
که سورة النجم آیت ۵۰۴
Page 7
سے احادیث کا مقام سنت رسول کے بعد اصول فقہ کی ترتیب میں تیسرے درجہ پر ہے.حدیث
کو تیسرے درجہ پر رکھنے کی وجہ صرف یہ ہے کہ جہاں سنت کو ہزاروں لاکھوں صحابہ، تابعین
اور تبع تابعین کے نسلاً بعد نسل تعامل و تواتر کی بناء پر غیر معمولی قطعیت حاصل ہوئی ہے وہاں تمام
احادیث کے ثبوت اور ان کی صحت کے بارے میں ایسی قطعیت کا دعویٰ نہیں کیا جا سکتا بلکہ اس میں بڑی
حد تک
تشخص کی گنجائش موجود ہے.دنیا میں حالات بدلتے رہتے ہیں اور نئے نئے مسائل پیدا ہوتے رہتے ہیں ان کے حل کے لئے بھی
ہمیں قرآن کریم، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور احادیث سے رہنمائی مل جاتی ہے بشرطیکہ تقوی اللہ
سے معمور ایسے مطہر وجو د میشتر آجائیں جن پر قرآن کریم کے ارشاد لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ دُ
کے مطابق خدا تعالیٰ کی طرف سے قرآنی علوم کے معارف کھولے جائیں نیز وہ حضرت محمد مصطفے صلی اللہ
علیہ وسلم کے ایسے کامل متبع ہوں کہ ان کی فطرت سنت رسول کے رنگ میں رنگین ہو چکی ہو.ہمارا یہ ایمان ہے کہ قرآن کریم کے اس وعدہ کے مطابق کہ
إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحفِظُونَه :
اس ذکر یعنی قرآن کریم کو ہم نے ہی اُتارا ہے اور ہم یقینا اس کی حفاظت کریں گے.اللہ تعالیٰ خود امت محمدیہ میں ایسے مطر وجود پیدا فرماتا رہتا ہے جو بدلتے ہوئے زمانہ کے تقاضوں
کو قرآن و سنت کی روشنی میں پورا کرنے کے اہل ہوتے ہیں اور تعلیم قرآن کی حفاظت کا کام اُن کے
سپرد کیا جاتا ہے.در حقیقت یہی لوگ ہیں جو مجتہد کہلانے کے مستحق ہیں جیسا کہ خلفائے راشدین اور دوسرے
ائمہ دین خصوصا امام ابوحنیفہ وغیرہ تھے.اس زمانہ میں خدا کی طرف سے مبعوث ہونے والے مبارک
وجود حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم و عدل ٹھہرایا ہے کہ پس آپ نے
قرآن و حدیث کی روشنی میں نئے پیدا شدہ فقہی مسائل کو حل کرنے اور استخراج احکام کے لئے اجتہاد
سے کام لینے کا جو محفوظ طریق بتایا ہے جماعت احمدیہ اس پر کاربند اور عمل پیرا ہے.اس بارہ میں حضور
علیہ السلام کے تفصیلی ارشادات "فقہ احمدیہ کے ماخذ کے عنوان کے تحت الگ درج کئے جا رہے
ہیں.ترجمہ : اس قرآن کی حقیقت کو وہی لوگ پاتے ہیں جو مطہر ہوتے ہیں.سورۃ الواقعہ آیت
سے سورۃ الحجر آیت ۱ کے بخاری کتاب الانبیاء باب نزول عیسی بن مریم
Page 8
حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے فرمودات پر با حسن طور عمل پیرا ہونے کی غرض سے حضرت امام
جماعت احمدیہ نے ایک مجلس افتار قائم فرمائی ہوئی ہے جو نئے پیدا ہونے والے مسائل پر غور و فکر کر کے
اپنی سفارشات حضرت امام جماعت احمدیہ کی خدمت میں پیشیں کرتی ہے اور آپ کی طرف سے منظوری
کے بعد ان سفارشات پر مبنی فیصلے " جماعت کے لئے واجب التعمیل ہوتے ہیں.کچھ عرصہ سے یہ ضرورت محسوس کی جا رہی تھی کہ اُن لوگوں کی رہنمائی کے لئے جو کسی فقہی مسئلہ
پر جماعت احمدیہ کا مسلک مستند طور پر جاننے کے خواہش مند ہوں مسائل فقہ کو مدون کر دیا جائے،
چنانچہ ء میں حضرت خلیفہ ایسیح الثالث رحمہ اللہ تعالیٰ نے جماعت احمدیہ کی مجلس شورای میں پاس شده
ریزولیوشن کے مطابق فقہ احمدیہ کی باقاعدہ تدوین کے لئے نو اراکین پرمشتمل ایک کمیٹی قائم فرمائی
جس نے یہ مسودہ مرتب کیا.تدوین فقہ کمیٹی کے لئے مندرجہ ذیل اراکین مقرر ہوئے :-
۱ - حضرت صاحبزادہ مرزا طاہر احمد صاحب ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز
خاکسار مرزا عبدالحق ایڈووکیٹ.صدر
-4
A
q
محترم شیخ محمد احمد صاحب مظہر ایڈووکیٹ
مجیب الرحمن صاحب ایڈووکیٹ
مولانا ابو العطاء صاحب فاضل (مرحوم)
شیخ مبارک احمد صاحب فاضل
میاں عبد السمیع صاحب نون ایڈووکیٹ
شیخ مظفر احمد صاحب ایڈووکیٹ
ملک سیف الرحمن صاحب مفتی سلسلہ عالیہ سیکرٹری
تدوین فقہ کا یہ کام مختلف مراحل میں سرانجام پایا.مسائل کو جمع کرکے اُن کی تحقیق و ترتیب اور
بنیادی مستودے کی تیاری میں محترم ملک سیف الرحمن صاحب ، حضرت مرزا طاہر احمد صاحب اور محترم
مولانا ابو العطاء صاحب مرحوم نے گراں قدر خدمات سرانجام دیں.اس طرح ایک بنیادی مسودہ تیار ہونے کے بعد دوسرے مرحلے پر محترم مجیب الرحمن صاحب
ایڈووکیٹ نے اس مسودہ کو دفعات کے پیرائے میں منتقل کیا اور مکرم مولوی محمد احمد صاحب ثاقب
فاضل کے تعاون سے متن کی تشریح لکھی اور حوالہ جات تیار کئے.وراثت سے متعلقہ مسائل میں مکرم
Page 9
پروفیسر عبد الرشید صاحب غنی نے قابل قدر مواد مہیا گیا.ان جملہ حضرات نے خاکسار سے مسلسل رابطہ رکھا اور اس طرح سے خاکسار کو اس
کام کی نگرانی
اور مناسب راہنمائی کا موقع ملا مسودہ تیار ہو جانے کے بعد تدوین فقہ کمیٹی نے مندرجہ ذیل اصحاب
کو مستودے پر تفصیلی غوروفکر کے لئے دعوت دی جنہوں نے اپنا قیمتی وقت صرف کر کے قابل قدر
مشورے دیئے اور اس کی تفصیلی خواندگی میں حصہ لیا :-
مکرم مولوی محمد احمد صاحب جلبیل فاضل مکرم چوہدری عزیز احمد صاحب ایڈووکیٹ ریٹائرڈ
ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ج.مکرم چوہدری اے وحید سلیم صاحب ایڈووکیٹ میکرم چوہدری اور میں نصرالله
خان صاحب ایڈووکیٹ.مکرم مرزا نصیر احمد صاحب ایڈووکیٹ میکرم چوہدری اعجاز نصراللہ خاں صاب
ایڈووکیٹ اور مکرم حمید اسلم صاحب ایڈووکیٹ.اس تفصیل سے ظاہر ہے کہ فقہ احمدیہ کا یہ مستو وہ جماعت احمدیہ کے مستند علماء اور قانون دان
حضرات کی نظر سے گذرا ہے.تمام اصحاب جنہوں نے اس کام کی تکمیل میں مدد دی ہے شکریے اور
دعا کے مستحق ہیں.فجزاهم الله تعالى احسن الجزاء
مکرم سید شمس الحق صاحب فاضل اور مکرم چوہدری ہادی علی صاحب نے حوالہ جات کی تلاش
تحقیق میں عرق ریزی سے کام لیا.فجزا ھما اللہ تعالی.فقہ احمدیہ کا جو حصہ اس وقت پیش کیا جا رہا ہے وہ نکاح اور اس سے متعلقہ امور اور
وراثت کے مسائل پر مبنی ہے.یہ حضرت مخلیفہ انسخ الرابع ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کی منظوری
کے بعد شائع کیا جا رہا ہے.جماعت احمدیہ اس فقہ کی پابند ہے اور یہ فقہ مندرجہ امور پر
جماعت احمدیہ کے فقہی مذہب کی مستند دستاویز ہے.اگر کسی مسئلے پر اس مجموعے میں کوئی اصول یا راہنمائی کر لے تو اس مسئلہ میں فقہ حنفیہ پر عمل
ہو گا سوائے اس کے کہ اس مجموعہ میں مندرجہ طریق کار کے مطابق بعد میں جماعتی اجتہاد کے ذریعے
اس میں کوئی تبدیلی کی جائے.خاکسار
مرزا عبد الحق
صدر تدوین فقہ کیٹی
Page 10
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
پیش لفظ
ایڈسین دوم -
نَحْمَدُهُ وَنَصَلَّى عَلَى رَسُولِهِ الكَرِيمُ
فقہ احمدیہ کا پہلا ایڈیشن چند دنوں میں ہی ختم ہو گیا تھا فالحمد للہ.اس لئے اب اس کا
دوسرا ایڈیشن شائع کیا جا رہا ہے.اس میں صفحہ 11 پر طلاق کے متعلق کسی قدر وضاحت کرنے کے لئے
کچھ اضافہ کیا گیا ہے باقی سب حسب سابق ہے.پہلے ایڈیشن کے پیش لفظ میں مجلس مشاورت شاہ کے اس ریزولیوشن کا ذکر رہ گیا تھا
جس میں فقہ احمدیہ کی تدوین کا فیصلہ کیا گیا تھا اب اس مجلس مشاورت کی کارروائی کا متعلقہ حصہ بھی اخبار
الفضل سے شامل اشاعت کیا جاتا ہے تا کہ اس فقہ کی تدوین کا پس منظر معلوم ہو سکے.د شاہ کی مجلس مشاورت کی ایک خصوصیت تھی کہ اس میں فقہ احمدیہ کی تدوین و ترتیب کے
متعلق تاریخی اہمیت کی حامل ایک اہم قرار داد بالاتفاق پاس کی گئی جس کے ذریعہ سیدنا
حضرت امام جماعت احمدیہ ایدہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں یہ درخواست
کی گئی کہ حضور ایک ایسی
کی بیٹی مقر فرمائیں جو فقہ احمدیہ کو مدون و مرتب کرے اور جو حضور کی منظوری سے کتابی صورت میں
شائع ہو کر جماعت کے ہر فرد کیلئے قضائیہ معاملات اور ملکی عدالتوں میں پرسنل لاء کا کام دے سکے "
فقہ احمدیہ کی تدوین کے متعلق تاریخی قرارداد
ر امان برش کو مجلس مشاورت کے آخری اجلاس میں سید نا حضرت امام جماعت احمدیہ رحمہ اللہ
تعالیٰ کی اجازت سے محترم جناب شیخ محمد احمد صاحب منظر ایڈووکیٹ نے فقہ احمدیہ کی تدوین کے سلسلہ
میں تاریخی اہمیت کی حامل ایک اہم قرار داد پیش فرمائی جس کے الفاظ یہ ہیں :-
و فقهی معاملات کے بارے میں حضرت بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ کا ارشاد حسب ذیل ہے :-
اگر حدیث میں کوئی مسئلہ نہ ملے اور نہ سُنت میں اور نہ قرآن میں مل سکے تو اس صورت
Page 11
میں فقہ حنفی پر عمل کر لیں کیونکہ اس فرقہ کی کثرت خدا کے ارادہ پر دلالت کرتی ہے اور اگر
بعض موجودہ تغیرات کی وجہ سے فقہ حنفی کوئی صحیح فتوی نہ دے سکے تو اس صورت میں
علماء اس سلسلہ کے اپنے خدا داد اجتہاد سے کام لیں، لیکن ہوشیار رہیں کہ مولوی عبداللہ
چکڑالوی کی طرح بے وجہ احادیث سے انکار نہ کریں ہاں جہاں قرآن اور سنت سے کسی حدیث
کو معارض پاویں تو اس حدیث کو چھوڑ دیں “
در یولو بر مباحثه چکڑالوی و بٹالوی صل است تصنیف نومبر ، روحانی خزائن جلد ۱۹ صلا(۲)
خدا تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ مندرجہ بالا تعلیم کی پابند رہی ہے اور رہے لیکن ابھی تک فقہ احمدیہ
پورے طور پر مدقون شکل میں جماعت کے سامنے نہیں آئی اس لئے :
مجلس شوری جو تمام جماعتہائے احمدیہ کی نمائندہ مجلس ہے حضرت امام جماعت ایدہ اللہ تعالے
بنصرہ العزیز کی خدمت میں مودبانہ درخواست کرتی ہے کہ حضور ایک سب کمیٹی مقر فرمائیں جو فقہ احمدیہ
کو مدون اور مرتب کرے اور یہ فقہ مسائل وراثت ہبہ انکاح، زکواۃ ، گارڈین شپ اور دیگر ضروری فقهی
امور پرمشتمل ہو جسے حضور ایدہ اللہ تعالیٰ کی منظوری کے بعد فقہ احمدیہ....یا مختصراً فقر احمدیہ کے نام
سے شائع کیا جائے تاکہ یہ فقہ جاعت احمدیہ کے ہر فردکے لئے قضائیہ معاملات اور ملکی عدالتوں میں پرسنل
لاء کا کام دے.مختلف نمائندگان نے اپنی آراء کا اظہار کرتے ہوئے اس قرار داد کا پر جوش خیر مقدم کیا اور جب
اسے رائے شماری کے لئے پیش کیا گیا تو جملہ نمائندگان نے متفقہ طور پر اس
کی تائید کی.یہ امر خاص
طور پر قابل ذکر ہے کہ حضرت امام جماعت احمدیہ نے بھی نمائندگان کے ہمراہ کھڑے ہو کر اس کے حق میں
اپنی رائے کا اظہار فرمایا.اس متفقہ سفارش کو حضور نے منظور فرمالیا.منقول از روزنامه افضل ۲۹ تاریخ ۶۹۶)
اس فیصلہ کے پیش نظر حضرت خلیفہ المسیح الثالث رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو کمیٹی تشکیل فرمائی تھی اس کا
ذکر ایڈیشن اول کے پیش لفظ میں موجود ہے.خاکسار
مرزا عبد الحق ایڈووکیٹ
صدر تدوین فقه کیشی
Page 12
لِسْمِ
الله الرّحمٰنِ الرَّحِيمِ
فقہ اسی سے کے مانند
تمند
قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی آخری اور کامل مشروعیت ہے اور تمام اسلامی قوانین
و احکام کا حقیقی، اصل اور بنیادی منبع ہے.چونکہ قرآن کریم میں کئی احکام اصولی اور اجمالی طور پر بیان ہوئے ہیں اس لئے بسا اوقات احکام
قرآنی کی تفصیل کے لئے سنت کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے اور انسی بناء پر اجتہاد کی ضرورت پیش آتی ہے.اجتہاد کے معنے یہ ہیں کہ بدلے ہوئے حالات کے تقاضا کے پیش نظر قرآن اور سنت میں بیان کردہ اصول
کی روشنی سے استفادہ یا شرعی امثال پر قیاس کر کے حسب ضرورت نئے احکام اخذ کئے جائیں.غرض نئی
ضرورتوں کے لئے مختلف مسلمہ ذرائع کی مدد سے نئے احکام اخذ کرنا اجتہاد کہلاتا ہے جس کے مختلف طریقے
ہو سکتے ہیں.اسی مفکر و تدبر اور شعوری کوشش کو اور اس کے نتیجہ میں مرتب شدہ احکام شریعت کو علم
فقہ کہا جاتا ہے.تمام فقہی مسائل کے لئے قرآن ، سنت اور حدیث بنیادی ماخذ ہیں.قیاس، استحسان، استدلال
استصحاب المحال اور عرف وغیرہ قرآن اور حدیث کے تابع اور مسائل فقہ کے ضمنی ماخذ ہیں.مذاہب فقہ
حنفی، مالکی ، شافعی ، جیلی یا اثنا عشری میں اختلاف ان بنیادی یا ضمنی ماخذ سے احکام کے استخراج و استنباط
اور اجتہاد کے طریق کار میں اختلاف کی وجہ سے ہوا ہے.جماعت احمدیہ صدقِ دل سے قرآن شریف کو آخری اور کامل شریعت مانتی ہے اسی طرح وہ
سنت و حدیث کے حجت شرعی ہونے کی بھی قائل ہے.پس فقہ احمدیہ کے بنیادی ماخذ اور مصادر قرآن،
سنت اور حدیث ہیں اور ثانوی مأخذ قیاس، استحسان وغیرہ ان بنیادی مصادر کے باہمی تعلق کی بابت
Page 13
جماعت احمدیہ اس عقید ہے پر قائم ہے کہ قرآن شریف کی کوئی آیت منسوخ نہیں لہذا فقہاء کے نزدیک
جو چیز نسخ قرآن بالقرآن یا نسخ قرآن بالسنہ کہلاتی ہے جماعت احمدیہ کے نزدیک اس
کی کوئی اہمیت نہیں
کیونکہ جماعت احمدیہ نسخ قرآن کی قائل ہی نہیں.اگر کسی جگہ حدیث قرآن سے مختلف نظر آئے تو اس اختلاف
کو دور کرنے اور ان دونوں میں تطبیق پیدا کرنے کی کوشش ہونی چاہیے اور اگر کسی طرح سے بھی تطبیق نہ ہو
سکے تو حدیث کو ترک کر دینے میں ہی برکت ہے کیونکہ قرآن کا فیصلہ اٹل ہے.فیقہ احمدیہ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں سنت اور حدیث کو ایک چیز نہیں مانا گیا کیونکہ
جماعت احمدیہ کے نزدیک سنت عملی تواتر کا نام ہے اور حدیث روایات کا مجموعہ ہے جنہیں بہت بعد میں
مدون کیا گیا تھا.جماعت احمدیہ کے بانی حضرت مسیح موعود و مہدی معہود علیہ الصلوۃ والسلام فقہ کے ماخذ کا ذکر
و
کرتے ہوئے فرماتے ہیں :." میرا مذ ہب یہ ہے کہ تین چیزیں ہیں کہ جو تمہاری ہدایت کے لئے خدا نے تمہیں دی ہیں.سب سے اول قرآن ہے جس میں خدا تی توحید اور جلال اور عظمت کا ذکر ہے...سوتم ہوشیار
رہو اور خدا کی تعلیم اور قرآن کی ہدایت کے برخلاف ایک قدم بھی نہ اٹھاؤ میں تمہیں
سچ سچ کہتا ہوں کہ جو شخص قرآن کے سات سو حکم میں سے ایک چھوٹے سے حکم کوبھی ٹا تھا
ہے وہ نجات کا دروازہ اپنے ہاتھ سے اپنے پر بند کرتا ہے“ نے
نیز فرماتے ہیں :." قرآن شریف جو کتاب اللہ ہے جس سے بڑھ کر ہمارے ہاتھ میں کوئی کلام قطعی اور
یقینی نہیں وہ خدا کا کلام ہے وہ شک اور فن کی آلائشوں سے پاک ہے " سے
دوسرا ذریعہ ہدایت کا جو مسلمانوں کو دیا گیا ہے سُنت ہے...مسلمانوں پر قرآن شریف
کے بعد بڑا احسان سنت کا ہے.خدا اور رسول کی ذمہ داری کا فرض صرف دو امر تھے
اور وہ یہ کہ خدا تعالیٰ قرآن کو نازل کر کے مخلوقات کو بذریعہ اپنے قول کے اپنے
منشاء سے اطلاع دے.یہ تو خدا کے قانون کا فرض تھا اور رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ه کشتی نوح صدا سن تصنیف در اکتوبر ۶۱۹۰۲، روحانی خزائن جلد ۱۹ ص۲
ه ریویو بر مباحثہ چکڑالوی و بٹالوی جنگ مین تصنیف نومبر ۶۱۹۰۲، روحانی خزائن جلد ۱۹ ص۲۹
Page 14
11
کا یہ فرض تھا کہ خدا کے کلام کو عملی طور پر دکھلا کر بخوبی لوگوں کو سمجھا دیں لے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم قرآن شریف کی اشاعت کے لئے مامور تھے.ایسا ہی سنت
کی اقامت کے لئے بھی مامور تھے.پس جیسا کہ قرآن شریف یقینی ہے ایسا ہی صنعت معمولہ ہے
متواترہ بھی یقینی ہے.یہ دونوں خدمات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے بجالائے ہے
سنت
سےمراد ہماری صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فعلی روش ہے جو اپنے اندر تواتر
رکھتی ہے اور ابتداء سے قرآن شریف کے ساتھ ظاہر ہوئی اور ہمیشہ ساتھ ہی رہے گی
یا یہ تبدیل الفاظ یوں کہہ سکتے ہیں کہ قرآن شریف خدا کا قول ہے اور سنت رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل اور قدیم سے عادت اللہ ہی ہے کہ انبیاء علیہم السلام خدا کا
قول لوگوں کی ہدایت کے لئے لاتے ہیں تو اپنے عملی فعل سے یعنی عملی طور پر اس قول کی
تفسیر کر دیتے ہیں تا اس قول کا سمجھنا لوگوں پر مشتبہ نہ رہے اور اس قولی پر آپ بھی عمل
کرتے ہیں اور دوسروں سے بھی عمل کراتے ہیں " سے
تیسرا ذریعہ ہدایت کا حدیث ہے کیونکہ بہت سے اسلام کے تاریخی اور اخلاقی اور فقہ
کے امور کو حدیثیں کھول کر بیان کرتی ہیں اور نیز بڑا فائدہ حدیث کا یہ ہے کہ وہ قرآن کی
خادم اور سنت کی خادم ہے اسے
سنت اور حدیث میں ما بہ الامتیاز یہ ہے کہ سنت ایک عملی طریق ہے جو اپنے ساتھ
تو اتر رکھتا ہے جس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے جاری کیا او وہ یقینی
مراتب میں قرآن شریف سے دوسرے درجہ پر ہے اور جس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
قرآن شریف کی اشاعت کے لئے مامور تھے ایسا ہی سنت کی اقامت کے لئے بھی مامور
تھے.میں جیسا کہ قرآن شریف یقینی ہے ایسا ہی سنت معمولہ متواترہ بھی یقینی ہے.یہ ونوں
خدمات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے بجا لائے اور دونوں کو اپنا فرض سمجھا.ه کشتی نوح شده من تصنیف ۶۱۹۰۲، روحانی خزائن جلد ۱۹ صلا
ه ریویو بر مباحثہ چکڑالوی و بٹالوی مد ین تصنیف نومبر ۶۱۹۰۲، روحانی خزائن جلد ۱۹ ص ۲
سے
را
را
را
را
را
ه کشتی نوح مده من تصنیف ۶۱۹۰۲، روحانی خزائن جلد ۱۹ صلا
".
Page 15
مثلاً جب نماز کے لئے حکم ہوا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا تعالیٰ کے اس قول کو
پنے فعل سے کھول کر دکھلا دیا اور عملی رنگ میں ظاہر کر دیا کہ فجر کی یہ رکعات ہیں اور
مغرب کی یہ.اور باقی نمازوں کے لئے یہ یہ رکعات ہیں.ایسا ہی حج کر کے دکھلایا اور پھر
اپنے ہاتھ سے ہزار ہا صحابہ کو اس فعل کا پابند کر کے تسلسلہ تامل بڑے زور سے قائم کر
دیا.پس عملی نمونہ جواب تک اُمت میں تعامل کے رنگ میں مشہود محسوس ہے.اسی کا نام
منت ہے.لیکن حدیث کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے روبرو نہیں لکھوایا اور نہ اس کے
جمع کرنے کے لئے کوئی اہتمام کیا.پھر جب وہ دور صحابہ رضی اللہ عنہم کا گذر گیا تو
بعض تابعین کی طبیعت کو خدا نے اس طرف پھیر دیا کہ حدیثوں کو بھی جمع کر لینا چاہیئے
تب حدیثیں جمع ہوئیں.اس میں شک نہیں کہ اکثر حدیثوں کے جمع کرنے والے بڑے متقی اور پر سہیز گار تھے
انہوں نے جہاں تک ان کی طاقت میں تھا حدیثوں کی تنقید کی اور ایسی حدیثوں سے
بچنا چاہا جو ان کی رائے میں موضوعات میں سے تھیں اور ہر ایک مشتبہ الحال راوی کی
حدیث نہیں لی.بہت محنت کی مگر تا ہم چونکہ وہ ساری کارروائی بعد از وقت تھی اس لئے
وہ سب ظن کے مرتبہ پر رہی بایں ہمہ یہ سخت نا انصافی ہوگی کہ یہ کہا جائے
کہ وہ سب حدیثیں لغو اور نکمتی اور بے فائدہ اور جھوٹی ہیں بلکہ ان حدیثوں کے لکھنے
میں اس قدر احتیاط سے کام لیا گیا ہے اور اس قدر تحقیق اور تنقید کی گئی ہے جو اس کی
نظیر دوسرے مذاہب میں نہیں پائی جاتی.تاہم یہ غلطی ہے کہ ایسا خیال کیا جائے کہ
جب تک حدیثیں جمع نہیں ہوئی تھیں اس وقت تک لوگ نمازوں کی رکعات سے بے خبر
تھے یا حج کرنے کے طریق سے نا آشنا تھے کیونکہ سلسلہ تعامل نے جو سنت کے ذریعہ
سے ان میں پیدا ہو گیا تھا تمام حدود اور فرائین اسلام ان کو سکھلا دیئے تھے اس لئے
یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ان حدیثوں کا دُنیا میں اگر وجود بھی نہ ہوتا جو مدت دراز کے بعد
جمع کی گئیں تو اسلام کی اصل تعلیم کا کچھ بھی حرج نہ تھا کیونکہ قرآن اور سلسلہ تعامل
نے ان ضرورتوں کو پورا کر دیا تھا تاہم حدیثوں نے اس نور کو زیادہ کیا گویا اسلام نور
عَلی نُور ہو گیا اور حدیثیں قرآن اور سنت کے لئے گواہ کی طرح کھڑی ہوگئیں اور اسلام.....
Page 16
۱۳
کے بہت سے فرقے جو بعد میں پیدا ہو گئے ان میں سے سینچے فرقہ کو احادیث صحیحہ سے
بہت فائدہ پہنچا ہے
سید نا حضرت مسیح موعود علیہ السلام مزید فرماتے ہیں :-
دو
ہماری جماعت کا یہ فرض ہونا چاہیے کہ اگر کوئی حدیث معارض اور مخالف قرآن اور
سنت نہ ہو تو خواہ کیسے ہی ادنی درجہ کی حدیث ہو اس پر وہ عمل کریں اور انسان کی
بنائی ہوئی فقہ پر اس
کو ترجیح دیں “ کے
ان تین رہنما محکم اصولوں کے بعد جن پر تمام شریعت حقہ کی بنیاد ہے اگر کوئی مسئلہ حل طلب
رہ جائے یا اس کے حل میں مزید روشنی اور راہنمائی کی ضرورت ہو یا کوئی نیا مسئلہ پیدا ہو جائے
تو ان مسائل کے حل کے لئے جماعت کے مجتہدین اور راسخین فی العلم کو حضرت بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ
کی حسب ذیل ہدایت ہے :-
اگر حدیث میں کوئی مسئلہ نہ ملے اور نہ سنت میں اور نہ قرآن میں مل سکے تو اس
صورت میں فقہ حنفی پر عمل کرلیں کیونکہ اس فرقہ کی کثرت خدا کے ارادہ پر دلالت کرتی
ہے اور اگر بعض موجودہ تغیرات کی وجہ سے فقہ حنفی کوئی صحیح فتوئی نہ دے سکے تو اس
صورت میں علماء اس سلسلہ کے اپنے خدا داد اجتہاد سے کام لیں لیکن ہوشیار رہیں کہ
مولوی عبداللہ چکڑالوی کی طرح بے وجہ احادیث سے انکار نہ کریں.ہاں جہاں قرآن او
سنت سے کسی حدیث کو معارض پاویں تو اس حدیث کو چھوڑ دیں " سے
حضور علیہ السلام حضرت امام ابو حنیفہ کے بارہ میں ایک جگہ فرماتے ہیں :-
وہ ایک بحر اعظم تھا اور دوسرے سب اس کی شاخیں ہیں ہیں کا نام اہل الرائے رکھنا
ایک بھاری خیانت ہے.امام بزرگ ابو حنیفہ کو علاوہ کمالات العلم انکار نبویہ کے استخراج
ریویو بر مباحثہ چکڑالوی و بٹالوی مثه سی تصنیف نومبر ۶۱۹۰۲، روحانی خزائن جلد ۱۹ ۲۰ تا صلا۲
"
"
رہ
"
"
"
سے
Page 17
۱۴
مسائل قرآن میں ید طولیٰ تھا.خدا تعالیٰ حضرت مجدد الف ثانی پر رحمت کرے انہوں نے مکتوب
م میں فرمایا ہے کہ امام اعظم صاحب کی آنے والے سینج کے ساتھ استخراج مسائل
قرآن میں ایک روحانی مناسبت ہے " ہے
حضور علیہ السلام ازالہ اوہام میں فرماتے ہیں :.اصل حقیقت یہ ہے کہ امام صاحب موصوف اپنی قوت اجتہادی اور اپنے علم اور
درایت اور فہم و فراست میں ائمہ ثلاثہ باقیہ سے افضل و اعلیٰ تھے اور ان کی خدا داد
قوت فیصلہ ایسی بڑھی ہوئی تھی کہ وہ ثبوت عدم ثبوت میں بخوبی فرق کرنا جانتے تھے
اور ان کی قوت مدرکہ کو قرآن شریف کے سمجھنے میں ایک خاص دستگاہ تھی اور ان کی
فطرت کو کلام الہی سے ایک خاص مناسبت تھی اور عرفان کے اعلیٰ درجہ تک پہنچ چکے
تھے اور اسی وجہ سے اجتہاد و استنباط میں ان کے لئے وہ درجہ علیا مسلم تھا جس بیت
پہنچنے سے دوسرے سب لوگ قاصر تھے “ کے
"
له الف :- الحق مباحثہ لدھیانہ سین تصنیف ۶۱۸۹۱ ۱۵۰ ، روحانی خزائن جلد ۴ ص
ب : نیز علامہ محد نجم الغنی خان صاحب رام پوری اپنی کتاب " مذاہب اسلام ص پر لکھتے ہیں
در مختار میں امام ابو حنیفہ کے جہاں اور اوصاف لکھے ہیں ان میں یہ بھی لکھا ہے يحكم بمذهبه
عیسی علیہ السلام یعنی امام ابو حنیفہ " کے مذہب کے موافق عیسی علیہ السلام حکم کریں گے او
محشی چلپی نے اس کا مطلب یوں بیان کیا ہے کہ حضرت شیخ اجتہاد کریں گے اور ان کا اجتہاد امام
ابو حنیفہ کے اجتہاد کے موافق پڑے گا.کے ازالہ اوہام سین تصنیف ۱۸۹۱ ۶ صفحه ۵۳۰، ۵۳۱، روحانی خزائن جلد ۳ صفحه ۳۸۵
Page 18
۱۵
استدراک
فقہ احمدیہ میں عام مدون فقہ حنفی سے بعض امور میں اختلاف کیا گیا ہے.یہ اختلاف فقہ حنفی
کے اصولوں سے باہر نہیں.پس جس طرح حضرت امام ابوحنیفہ سے آپ کے بعض شاگردوں مثلاً حضرت
امام ابویوسف یا حضرت امام محمد کا اختلاف فقہ حنفی کے دائرہ سے ان کو باہر نہیں لے جاتا اور ان کے
اس اختلاف کو فقہ حنفی کی مخالفت نہیں سمجھا جاتا اسی طرح فقہ احمدیہ کا لبعض امور میں اختلاف فقہ
حنفی کے مخالف قرار نہیں دیا جا سکتا خصوصاً جبکہ یہ اختلاف انہی اصولوں پر مبنی ہے جنہیں فقہاء
حنفی تسلیم کرتے ہیں کیونکہ فقہ احمدیہ کے وہی ماخذ ہیں جو فقہ حنفی کے ہیں.
Page 19
14
تعریف نکاح
دفعہ نمبر ا
نکاح مرد اور عورت کے درمیان شارع کی عائد کردہ شرائط کے
مطابق ایک شرعی معاہدہ ہے جو جنسی جبلت کو حدود اللہ کا پابند کر کے فریقین
کے درمیان جنسی تعلق کو جائز اور اولاد کے نسب کو صحیح ٹھراتا ہے.تشریح شریعت کی اصطلاح میں نکاح ایک معاہدہ ہے جس کا مقصد جائز اولاد پیدا کرنا ہےلیے
چونکہ اسلام دین فطرت ہے اس لئے اس نے طبعی حوائج اور جبلی ضروریات کو گلینہ نظر انداز کرنے
یا دبانے کی اجازت نہیں دی اور تجرد اور جنسی تعلقات سے اجتناب کی زندگی کو سخت نا پسند
فرمایا ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اِنَّ الرَّهْبَانِيَّةَ لَمْ تُكْتَبُ عَلَيْنَا
یعنی رہبانیت اور ترک دنیا کا ہمیں حکم نہیں دیا گیا.ایک اور مشہور عوام حدیث ہے :-
لے فقہاء نے نکاح کی اصطلاحی تعریف یہ کی ہے :-
النكَاحُ فِي الشَّرْعِ عَقْدُ مَدْنِيُّ لَفْظِيُّ اَوْخَطِيُّ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَا
بالِغَيْنِ رَاشِدَيْنِ يَحْفَطَانِ بِهِ عَلَيْهِمَا عِفَا فَهُمَا وَصَلَا حَهُمَا ثُمَّ
وَمَلَاحَهُمَا
يَنْشَأْنِ مِنْهُ أَسْرَةً - الاسرة فى الشرع الاسلامي مك مرتبه عمر فروخ بیروت لبنان)
یعنی نکاح ایک تمدنی معاہدہ ہے جو عاقل بالغ مرد اور عاقلہ بالغہ عورت آپس میں
زبانی یا تحریری طور پر کرتے ہیں اور اس کی غرض یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کے ذریعہ اپنی عفت
کی حفاظت کریں اور بھلائی کا سامان کر کے ایک گھر آباد کریں تا کہ اس سے گنبہ کی بنیا د پڑے.کے مسند احمد بن حنبل جلد ۶ ۲۲۵
Page 20
16
تار بانِيَّةَ فِي الْإِسْلامِ کہ اسلام میں مجرد رہنے اور دنیا ترک کر دینے کی کوئی ہدایت
نہیں اور نہ ہی اس کے پسندیدہ ہونے کی کوئی سند ہے.اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ صحابہ نے یہ فیصلہ کیا
کہ وہ نمازیں پڑھیں گے، روزے رکھیں گے اور عمر بھر شادی نہیں کریں گے.یہ بات آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا :-
" کیا ان لوگوں
کو معلوم نہیں کہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں.روزے بھی
رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں اور میں نے شادیاں بھی کی ہیں "
اسی سلسلہ میں آپؐ نے فرمایا :-
نکاح میری سنت ہے اور جو شخص میری سنت کو ترک کرتا ہے میرا اس سے کوئی
تعلق نہیں "
اس حدیث کے ایک حصہ کے الفاظ یہ ہیں :-
و - " اَتَزَوَّجُ النِّسَاء فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنى به
ب - " التعَامُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلُ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنَى سے
آپ نے یہ بھی فرمایا :
" مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجُ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ له
یعنی تم میں سے جو شادی کی توفیق رکھتا ہے اسے چاہیے کہ شادی کرے کیونکہ شادی نظر
نیچی رکھنے اور پاکدامن رہنے کا بہترین ذریعہ ہے.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ارشاد میں فَلْيَزَوجہ کا لفظ استعمال فرمایا جو امرکا صیغہ ہے
لا رهبانية في الإسلام - المبسوط سرخسى بالا - یہ الفاظ حدیث کی کسی کتاب میں نہیں ملتے البتہ
ابوداؤومن لا صَيرُ ورَة فِي الْاِسلام کے الفاظ مروی ہیں.صیرورہ کے معنے ہیں انقطع عن
النكاح وتبتل - ابو داؤد کتاب المناسك باب لا صيرورة نیز دیکھیں مکتوبات سلیمانی جلد احث ۲۱
بخاری کتاب النکاح باب ترغیب النكاح جلد ۲ ص
ه ابن ماجه کتاب النکاح باب فضل النكاح ص۱۳
که ابو داؤد کتاب النکاح باب التحريض على النكاح جلد اول ص ۲۷
٢٤٩
Page 21
اور اصولاً وجوب پر دلالت کرتا ہے.اسی طرح قرآن کریم کا ارشاد ہے :-
وَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتِى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ
مَثْنى وَتُلتَ وَرُبع : فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ
أيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا له
یعنی اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ تم بیوہ عورتوں سے انصاف نہ کر سکو گے تو جو صورت تمہیں
پسند ہو کر لو یعنی حسب پسند دو دو سے اور تین تین سے اور چار چار سے نکاح کر لولیکن
اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ تم عدل نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی عورت سے یا اُن لونڈیوں سے جو
تمہارے ہاتھوں میں ہیں نکاح کرو.یہ طریق اُس بات کے بہت قریب ہے کہ تم ظلم و تعدی
سے بچے جاؤ.اس ارشادربانی میں " فانکحوا کے صیغہ سے صاف ظاہر ہے کہ صاحب استطاعت کیلئے
نکاح واجب ہے.دفعہ نمبر ۲
مقاصد نکاح
نکاح کا مقصد بقاء نسل انسانی تحفظا عفت حصول مودت اور سکینت پر مبنی
پر امن عائلی زندگی کی ضمانت مہیا کرنا ہے.تشریح
قرآن کریم میں شادی شدہ مرد اور عورت کو محصین اور محصنہ کہا گیا ہے یہ جس کے معنے قلعہ بند
له سورة النساء آیت م
له سورة النساء آیت ۲۵
Page 22
19
ہو جانے کے ہیں.اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ شادی کا مقصد مرد اور عورت کو شیطانی وساوس
اور شہوانی حملوں سے محفوظ رکھنا ہے گویا تحفظ عفت اور تقوی شعار زندگی نکاح کے اہم مقاصد میں
شامل ہے.اسی طرح نکاح کے ذریعہ سے نسل انسانی کی بقاء نسب کا تحفظ اور عائلی زندگی کو مضبوط بنیادوں
پر قائم کرنا بھی مقصود ہے.دفعہ نمبر ۳
ه
المبيت نکاح
ہر عاقل، بالغ احمدی نکاح کرنے کا اہل ہے
تشریح چونکہ کان کے نتیجہ میں فریقین پر ایسے حقوق وفرائض عائد ہوتے ہیں جس کے فریقین شرعًا
اور قانوناً پابند ہوتے ہیں اس لئے اس معاہدہ کے دو بنیادی اوصاف یعنی عقل اور بلوغت کا پایا جانا
ضروری ہے.یہی وجہ ہے کہ مجنون ، فاتر العقل اور نا بالغ خود اپنا نکاح کرنے کے اہل نہیں ہیں ہاں ان کی
طرف سے ان کے ولی یہ معاہدہ کر سکتے ہیں.ایسی صورت میں فاتر العقل یا نا بالغ کا ولی بوجہ نیابت منکوحہ
کے نان و نفقہ اور مہر کا ذمہ دار ہوگا.تے
لے سوال : اگر نابالغ لڑکے یا لڑکی کا نکاح اس کا ولی کر دے اور ہنوز وہ نابالغ ہی ہو اور ایسی ضرورت
پیش آو سے تو کیا طلاق بھی ولی دے سکتا ہے یا نہیں ؟
جواب :- حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ دے سکتا ہے؟
بدر ۲۵ جولائی شاه بحوالہ فتاوای مسیح موعود )
Page 23
ت
لعه نمبر۴
نکاح کی اغراض کے لئے مرد اور عورت کی بلوغت طبعی کافی اور معتبر ہے
تاہم ملکی حالات اور علاقہ کی آب و ہوا کو ملحوظ رکھتے ہوئے مرد اور عورت کی
بلوغت کی اوسط عمر متعین کرنے کے لئے مناسب قانون بنایا جا سکتا ہے.تشریح
اغراض نکاح کے لئے شرعاً لڑکا یا لڑکی اُس وقت بالغ سمجھے جائیں گے جب وہ جسمانی نشو و نما
کے اعتبار سے بالغ ہو جائیں گے جس کی ایک طبعی علامت لڑکے کے لئے احتلام اور لڑکی کے لئے حیض کا
شروع ہوتا ہے.ہے.بلوغت کی یہ عمر خاندانی حالات ، خوراک، صحت اور ملکی آب و ہوا کے اعتبار سے مختلف ہو سکتی
اگر یکیسانی کی غرض سے قانون کا تقاضا ہو تو مختلف اغراض کے لئے بلوغت کی عمر سالوں میں بھی معین
کی جا سکتی ہے.مثلاً شادی کی اغراض کے لئے لڑکے کی عمر ۱۸ سال اور لڑکی کی عمر 14 سال مقرر کی جاسکتی
ہے.اسی طرح مالی تصرف کے لئے لڑکے لڑکی کی عمر اٹھارہ سال تجویز کی جاسکتی ہے اور اس میں کوئی
شریعی روک نہیں.
Page 24
۲۱
دفعہ نمبره
رضا
عاقل بالغ مرد اپنے نکاح کے لئے خود رضامندی دے گا البتہ عاقل بالغ
عورت
کی اپنی رضامندی کے علاوہ اس کے ولی کی رضامندی بھی ضروری ہے.تشریح
چونکہ نکاح سے متعلق مجملہ حقوق و فرائض براہِ راست مرد سے وابستہ ہیں جیسے حق مہر کی
ادائیگی، بیوی اور بچوں کے نان و نفقہ کی ذمہ داری اور ان حقوق و فرائض کی ادائیگی کیسی وکیل یاولی کے
ذمہ واجب نہیں ہوتی اس لئے صحت نکاح کے لئے عاقل بالغ مرد کی اپنی رضامندی ہی کافی اور معتبر ہے.البتہ اگر مرد نا بالغ یا مجنون ہو تو اس کے ولی کی رضامندی ضروری ہوگی اور وہ بھی ان مالی حقوق
کی ادائیگی کا ذمہ دار ہو گا جو نکاح کے نتیجہ میں خاوند کے ذمہ عائد ہوتے ہیں.عورت کی اپنی رضامندی کے ساتھ اس کے ولی کی رضا مندی بھی ضروری ہے.اس بارہ میں فصل
بحث زیر دفعہ و تشریح شرط ۲ ۳۵ دیکھیں.دفعہ نمبر ۶
کفائت
نکاح میں مرد کا عورت کے لئے کفو ہو نامستحسن ہے
تشریح کھو کے لفظی معنے ہم پلہ اور برا بر ہونے کے ہیں فقہاء نے بعض دائروں میں کمو عینی
Page 25
۲۲
مرد کا اس کے ہم پلہ ہونے کی معاشرتی اہمیت کو تسلیم کیا ہے کیونکہ کفایت کا اصل مقصد فریقین کی ازدواجی
زندگی میں ہم آہنگی اور موافقت پیدا کرنا ہے.کفویں مذہب، دینداری اور معاشرتی یکسانی کو بنیادی حیثیت حاصل ہے.اس کے علاوہ نسب
پیشہ، تعلیم اور عمر وصحت کو بھی مد نظر رکھ لیا جائے تو اس میں برکت اور معاشرتی بہتری ہے.تاہم اگر مرد اور
عورت اور اس کا ولی اس دوسرے درجہ کے تفاوت کو علم کے باوجود نظر انداز کر دیں تو شر کا نکاح مجمل
ہوگا اور اس تفاوت کی وجہ سے اس نکاح کے فسخ کئے جانے کے مطالبہ کا کوئی جواز نہ ہوگا.بهر حال اِن سب امور میں سے دینی کفائت اور مساوات کو بنیادی اہمیت حاصل ہے.اسی بناء
پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-
تُنْكَحُ الْمَرأَةُ الأَرْبَعِ لِمَا لِهَا وَ لِحَسْبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظُفُرُ
بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ " له
یعنی اہلی زندگی کو خوش گوار بنانے کے لئے کیسی عورت سے شادی کرنے کے سلسلہ میں
جن باتوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے ان میں مندرجہ ذیل چار امور کو زیادہ اہمیت حاصل
ہوتی ہے.اقول عورت کے خاندان کی مالی حالت ، دوئم عورت کی خاندانی وجاہت ،
سوئم عورت کا حسن و جمال اور چہارم عورت کی دینداری اور اس کی حسین سیرت.تاہم
ایک مومن کو چاہیے کہ وہ حسن سیرت اور دینداری کے پہلو کو ترجیح دے.ایسی ہی تمدنی، معاشرتی اور تربیتی وجو ہات
کی بناء پر پیدا ہونے والے مسائل اور اُلجھنوں
کے پیش نظر جماعت احمدیہ ایک احمدی عورت کو اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ کسی غیر احمدی
مرد سے شادی کرے.ایسی شادی کفائت کے دینداری والے معیار پر پوری نہیں اُترتی تاہم اگر نظام
جماعت کی خلاف ورزی میں ایسی شادی ہو جائے تو اسے باطل قرار نہیں دیا جائے گا یعنی ایسے
نکاح کے بعد پیدا ہونے والی اولا د ثابت النسب ہوگی اسے سارے شرعی اور قانونی حقوق حاصل
ہوں گے اور وہ وراثت کی حقدار ہوگی.سے
له بخاری کتاب النکاح باب الاكفاء في الدين جلد ۲ ص۷۶
ے مزید تفصیل کے لئے دیکھیں دفعہ نمبر ۱۴ ۷ انکاح فاسد اور ثبوت النسب.16
Page 26
۲۳
دفعہ نمبر
تشریح
انعقا د نکاح
نکاح فریقین کے ایجاب و قبول اور معروف طریقہ پر اس کے اظہار
سے منعقد ہوتا ہے.یہ ایجاب و قبول ایک ہی مجلس میں ہوا اور اس کا عام اعلان
ہو.ک :- ایجاب و قبول کے معنے ہیں کہ ایک فریق کی طرف سے مقرر کردہ شرائط کے مطابق نکاح
کی تجویز ہوا اور دوسرا فریق اسے قبول کرے...معاہدہ نکاح میں ایجاب عموماً عورت کی جانب سے ہوتا ہے قبول مرد کی جانب سے لیکن ایسا
ہونا ضروری نہیں پہلا قول خواہ کیسی فریق کی جانب سے ہو ایجاب کہلائے گا اور دوسرے کی جانب سے
اس کا مثبت جواب قبول کہلائے گا.بعض صورتوں میں جب ایک ہی شخص دونوں جانب سے ولی یا وکیل ہو تو وہ خود ایجاب و قبول
کر سکتا ہے.ایجاب و قبول کے لئے الفاظ کی کوئی پابندی نہیں.الفاظ خواہ کچھ ہوں لیکن واضح اور غیر مہم
ہونے چاہئیں جن سے نکاح اور باہمی رشتہ ازدواج پر رضامندی کا اظہار ہو اور ایسے اظہار
سے نکاح پر رضا مندی کے علاوہ اور کوئی مفہوم نہ نکلتا ہوئے
اگر فریقین میں سے کوئی ایک گونگا اور بہرہ ہو تو اشارہ کے ذریعہ سے بھی ایجاب و قبول ہو
سکتا ہے بشرطیکہ اشارہ واضح ہوا اور اس سے یہ مفہوم نکلتا ہو کہ فریقین زوجیت کے رشتہ میں
ه زبانی اظہار کے علاوہ تحریری طور پر بھی رضامندی کا اظہار کیا جائے تو بلحاظ ثبوت ایسا ایجاب
و قبول زیادہ معتبر اور مستند ہوگا.
Page 27
۲۴
منسلک ہو رہے ہیں اور اس پر وہ رضا مند ہیں.ب :.ایک ہی مجلس میں ایجاب و قبول
مجلس نکاح میں ایجاب و قبول اصالتا بھی ہو سکتا ہے اور وکالتا بھی یعنی لڑکی کے لئے خود مجلس
میں حاضر ہو گر ایجاب یا قبول کرنا لازمی نہیں اس کا وکیل اس کی طرف سے رضا مندی کا اظہار کر سکتا ہے
اور معروف کے لحاظ سے یہ طریق زیادہ پسندیدہ ہے.اسی طرح لڑکا بھی اگر مخلتیں نکاح میں موجود نہ ہو تو اس کا وکیل اس کی طرف سے ایجاب یا
قبول کر سکتا ہے.البتہ ایسی صورت میں ضروری ہے کہ جو فریق موجود نہیں وہ مستند اور قابل اعتماد
زبانی یا تحریری ثبوت کے ذریعہ اپنی رضامندی ظاہر کرے اور اس کی طرف سے وکیل کے تقریر کا ثبوت
موجود ہو.ج : نکاح کا مناسب اعلان ضروری ہے.نکاح کا اعلان ایسے رنگ میں ہونا چاہیئے کہ عام لوگوں کو اس کا علم ہو جائے.آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کا اعلان کرو خواہ دن کے ذریعہ ہو.حدیث کے الفاظ یہ ہیں :-
اعْلِمُوا هَذَا التَّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدَّتِ له
" یعنی نکاح کا اعلان کرو مسجد میں پڑھاؤ اور اس کے اعلان کے لئے دن بجاؤ"
موجودہ دور میں اخبارات اور رسائل کے ذریعہ بھی اعلان کیا جاسکتا ہے.خفیہ نکاح اگرچہ گواہان موجود ہوں ناپسندیدہ ہے.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ نکاح
کے متعلق فرمایا :
" لا نِكَاحَ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِشَهُودٍ الْبَغَايَا اللَّاتِي يَنْكِحْنَ اَنْفُسَهُنَّ
بغير بينة
یعنی بینہ اور گواہوں کے بغیر نکاح درست نہیں.وہ عورتیں بدکردار ہیں جو شریعیت کے
بیان کردہ اصول کے مطابق بقیہ قائم کئے بغیر اپنا نکاح خود کر لیتی ہیں.ے ترندی کتاب النکاح باب اعلان النکاح و ابن ماجه ص۱۳
کے اعلان کے ذرائع سے گریز کیا جائے.خبر کو پھیلنے سے روکا جائے.کے ترندی کتاب النکاح باب لا نكاح الابينة من
Page 28
۲۵
نکاح کا اخفاء اگر فاشند اغراض پر مبنی ہو تو عدالت یا قضاء ایسے خفیہ نکاح کو نا جائز قرار دے سکتی
ہے جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایک ارشاد سے ظاہر ہے جسے حضرت امام مالک نے اس طرح روایت
کیا ہے :.الى الزبيرِ الْمَلّي ان عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أُتِيَ بِنِكَاحِ لَمْ يُشْهَدْ عَلَيْهِ
الارجل وَامْرَأَةٌ فَقَالَ هَذَا نِكَامُ السّروَلَا أُجِيزُهُ وَلَوْ كُنْتُ
تَقَدَّمُتُ فِيهِ لَرَجَمْتُ له
یعنی ابی الزبیر مکتی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک مرد اور عورت کے
نکاح کا معاملہ پیش کیا گیا جس کے صرف ایک مرد اور ایک عورت گواہ تھے اور وہ عام
مجلس میں نہیں پڑھا گیا تھا اس پر آپ نے فرمایا " یہ تو خفیہ نکاح ہے میں اسے جائز نہیں
سمجھتا اور اگر نہیں نے اس سے پہلے اس قسم کے نکاح کے ناجائز ہونے کا اعلان کیا ہوتا
تو میں ان دونوں کو اس خلاف ورزی کی سخت سزا دیتا.لے مثلاً کو رکھنا کو
مثلاً پہلی بیوی سے اس نکاح کو خفیہ رکھنا مقصود ہوتا کہ اس کے حقوق کو نظر انداز
کیا جا سکے.کے موطا امام مالك باب ما لا يجوز من النكاح ص19
Page 29
Σ
دفعه نمبر
صحت نکاح اور اسکی شرائط
صحت نکاح کے لئے تین بنیادی شرائط ہیں.نمبرا : عورت موانع سے خالی ہو.نمبر ۲ : عورت اور اس کا ولی دونوں اس نکاح پر راضی ہوں.نمبر : معاہدہ نکاح کے کم از کم دو گواہ ہوں.تشریح شرط نمبر ا موانع نکاح
عورت کے موانع نکاح سے خالی ہونے سے مراد یہ ہے
کہ اس میں کوئی ایسی وجہ نہ ہو جس کی بناء پر
اس مرد کا اس عورت سے نکاح نہ ہو سکتا ہو.ایسی عورتیں جن سے اس قسم کے مواقع کی وجہ سے نکاح نہیں ہو
سکتا "محترمات“ کہلاتی ہیں اور ان کی دو قسمیں ہیں.ابدی محرمات : یعنی ایسی عورتیں جن سے کبھی بھی نکاح جائز نہ ہو.وقتی محرمات :.یعنی ایسی عورتیں جن سے نکاح کسی شرعی روک کی وجہ سے جائز نہ ہوا اور اس روک کے
دُور ہو جانے پر نکاح جائز ہو جائے.ہر قسم کی محرمات کا بیان قرآن کریم کی سورۃ النساء کی آیت نمبر ۲۴، ۲۵ میں ہے.چنانچہ فرمایا :-
حرمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهُتُكُمْ وَبَنْتُكُمْ وَاَخَوتُكُمْ وَعَمَّتُكُمْ وَخَلَتُكُمْ وَبَنتُ
الآخر وَبَنْتُ الْأَخْتِ وَ أَمَّمْتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَآخَوتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ
وا مَّمْتُ نِسَائِكُمْ وَرَبابِبْكُمُ الّتي في حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَا بِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ
بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا وَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَابِلُ ابْنَا بِكُمُ
الَّذِينَ مِنْ أَصْلَا بِكُمْ وَ اَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ
Page 30
۲۷
كَانَ غَفُورًا رَّحِيْمَان وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
كِتَبَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَأَحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُّحْصِنِينَ
غَيْرَ مُسْفِحِينَ ، فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَاتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً
ولا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
حكيما 0
تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں
اور تمہاری بھتیجیاں اور تمہاری بھانجیاں اور تمہاری رضاعی مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا
ہوا اور تمہاری رضاعی بہنیں اور تمہاری ساسیں اور تمہاری وہ سوتیلی لڑکیاں جو تمہاری ان
بیویوں سے ہوں جن سے تم خلوت کر چکے ہو اور وہ تمہارے گھروں میں پلتی ہوں تم پر
حرام کی گئی ہیں، لیکن اگر تم نے ان ماؤں سے خلوت نہ کی ہو تو اُن کی لڑکیوں سے نکاح کرنے
میں تم پر کوئی گناہ نہیں اور اسی طرح تمہارے ان بیٹیوں کی بیویاں جو تمہاری پشت سے
ہوں تم پر حرام ہیں اور یہ بھی کہ تم دو بہنوں کو اپنے نکاح میں جمع کر و.ہاں جو گزر گیا سو
گزر گیا.اللہ یقینا بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے.اور پہلے سے منکوحہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں باستثنا ان عورتوں کے جو تمہاری
ملکیت میں آجائیں.یہ اللہ نے تم پر فرض کیا ہے اور جوان اوپر کی بیان کہ وہ عورتوں
کے سوا ہوں وہ تمہارے لئے بعد نکاح حلال ہیں.یعنی اس طرح سے کہ تم اپنے مالوں کے
ذریعہ سے انہیں طلب کر و بشر طیکہ تم شادی کرنے والے ہو زنا کرنے والے نہ ہو.پھر دی شرط
بھی ہے کہ اگر تم نے ان سے نفع اُٹھایا ہو تو تم انہیں ان کے مہر بہ مقدار موعود ادا کرو.اور مہر مقرر ہو جانے کے بعد جس کمی بیشی پر تم باہم راضی ہو جاؤ اس کے متعلق تمہیں کوئی
گناہ نہ ہوگا.اللہ یقیناً بہت جاننے والا اور حکمت والا ہے.ابدی محترمات (بر بنائے نسب)
ا : وہ عورتیں جو مرد کے اصول میں شمار ہوتی ہیں ان سے نکاح ابدی حرام ہے مثلاً ماں ، نانی،
له سورة النساء آیت ۲۵۲۴
Page 31
۲۸
دادی وغیرہ.ماں کی مرمت نص صریح سے ثابت ہے جیسا کہ فرمایا :-
حُرمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهُتُكُمْ
یعنی تم پر تمہاری مائیں حرام ہیں.امهات ، امم کی جمع ہے جس کے معنے ہیں ماں.اور اس جگہ حقیقی ماں کے علاوہ نانی اور دادی
وغیرہ بھی مراد ہیں.اِس طرح نانی اور دادی سے صرف ماں کی ماں اور باپ کی ماں مراد نہیں بلکہ ماں کی
ماں اور اس سے اوپر کی مائیں یعنی نانی پڑ نانی وغیرہ اور دادی سے دادی پڑ وادی وغیرہ سبھی مراد ہیں.ب :.وہ عورتیں جو مرد کی فرغ میں شمار ہوتی ہیں ان سے نکاح ابدی حرام ہے مثلا بیٹی ،
ہوتی، نواسی وغیرہ.بیٹی کی حرمت نص صریح سے ثابت ہے جیسا کہ فرمایا :-
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهُتُكُمْ وَبَنْتُكُمْ ہے
یعنی تم پر تمہاری مائیں اور بیٹیاں حرام ہیں.بیٹی کے مفہوم میں نواسی ، پوتی وغیرہ بھی آجاتی ہیں.احادیث میں ان سب کے لئے بنت کا
لفظ استعمال ہوا ہے.ج :- وہ عورتیں جو باپ یا ماں کی فرع یعنی اولاد ہیں ان سے نکاح ابدی حرام ہے مثلاً بہن ،
بھانجی بھیجی.بہنوں کی حرمت اور بھانجیوں اور بھتیجیوں کی محرمت نص صریح سے ثابت ہے جیسا کہ فرمایا:.وَآخَوتُكُمْ.....وَ بَنتُ الْآخِر وَبَنْتُ الأُخْتِ لَه
یعنی تم پر تمہاری بہنیں حرام ہیں اسی طرح بھائی کی بیٹیاں اور بہن کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں
اور بھانجیاں سب حرام ہیں.بہن سے مراد تمام قسم کی بہنیں ہیں خواہ وہ حقیقی ہوں یا سوتیلی.اور سوتیلی بہن
سے مراد باپ کی طرف سے یا ماں کی طرف سے ہر دو طرح کی بہنیں ہیں کیونکہ ان سب پر بہن
کے لفظ کا اطلاق ہوتا ہے.بہنوں اور بھائیوں کی اولاد مثلاً بھانجی بھتیجی اور ان کی
اولاد سب ابدی حرام ہیں.2: وہ عورتیں جو مرد کے اپنے اصل بعید ( دادا پڑدادا وغیرہ) کی فرع قریب ہوں صرف ان
سے نکاح ابدی حرام ہے ان کی اولاد سے نہیں مثلاً پھوپھی اور خالہ وغیرہ سے تو نکاح حرام ہے لیکن
لے لے کے سورۃ النساء آیت ۲۴ :
Page 32
۲۹
ان کی اولاد سے جائز ہے.پھوپھی اور خالہ وغیرہ کی حرمت نفق صریح سے ثابت ہے جیسا کہ فرمایا.وَعَمْتُكُمْ وَخُلتُكُمْ
یعنی تم پر تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں بھی حرام ہیں.دادا کی بہن یعنی باپ کی پھوپھی اور نانا کی بہن یعنی ماں کی پھوپھی اور اسی طرح باپ کی خالہ اور ماں کی
خالہ بھی اس محرمت میں شامل ہیں کیونکہ رشتہ میں وہ بھی پھوپھیاں اور خالائیں ہی ہیں.پھوپھی اور خالہ وغیرہ کی اولاد سے شادی جائز ہے کیونکہ آیت حرمت میں جہاں بہنوں کی حرمت
کا ذکر ہے وہاں بہنوں کی اولاد کی حرمت کا ذکر بھی واضح الفاظ میں ہے لیکن خالہ اور پھوپھی کی حرمت کے
ساتھ ان کی اولاد کی حرمت کا ذکر نہیں جو اس بات کی دلیل ہے کہ پھوپھی اور خالہ کی اولاد سے نکاح جائز
ہے اور تعامل بھی اس کے مطابق ہے کیونکہ پھوپھی اور خالہ کی حرمت اور ان کی اولاد کی عدم حرمت ہر کسی کے
کے فقہاء کے درمیان متفق علیہ ہے.ابدی محرمات ( بر بنائے مصاہرت )
: اپنے باپ کی منکوحہ سے نکاح ابدی حرام ہے ، باپ کی منکوحہ سے نکاح کی حرمت نقض قرآنی سے
ثابت ہے جیسا کہ فرمایا :-
لا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ ا باؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ له
یعنی ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں.اس حکم میں دادا کی منکوحہ اور نانا کی منکوحہ شامل ہیں کیونکہ عربی لغت کے مطابق " آب " سے مراد
باپ اور باپ سے اوپر کے تمام آباد یعنی دادا نانا وغیرہ بھی شامل ہیں لہذا ان کی منکوحہ بھی باپ کی منکوحہ
کے حکم میں شامل ہوگی.باپ کی منکوحہ کی حرمت محض عقد صحیح سے لازم آجاتی ہے مجاموت اور مباشرت شرط
لازمی نہیں.ب :.ساس.ساس کی ماں.ساس کی دادی ونانی وغیرہ سے نکاح ابدی حرام ہے.ساس اور ساس کی
ماں وغیرہ کی حرمت بھی نص صریح سے ثابت ہے جیسا کہ فرمایا :-
سورة النساء آیت ۲۳
Page 33
وامهت
ت نِسَائِكُم
اور تمہاری بیویوں کی مائیں بھی تم پر حرام کی گئی ہیں.بعض فقہاء نے اس بارے میں اختلاف کیا ہے کہ محض نکاح سے ہی اس کی ماں اور دادی وغیرہ کی
حرمت ثابت ہو جاتی ہے یا مجامعت کا ہونا اس حرمت کے لئے ضروری شرط ہے.جو لوگ بیوی کے ساتھ
مجامعت کو اس حرمت مصاہرت کی شرط سمجھتے ہیں ان کا استدلال یہ ہے کہ آیت کریمہ و اصلتُ نِسَائِكُم
وربالبكم التي في حُجُورِكُم مِّن نِسَائِكُمُ التِي دَخَلْتُمْ بِهِی میں دَخَلْتُمْ بِهِنَّ کی شرط کا
تعلق " امھات اور ربائب“ دونوں کے ساتھ ہے لہذا جب تک مجامعت نہ ہو نہ ساس سے نکاح حرام
ہے اور نہ ربیبہ کی حرمت لازم آتی ہے اس کے برعکس جمہور فقہاء اور جماعت احمدیہ کا مذہب یہ ہے کہ
محض نکاح سے ہی بیوی کی ماں وغیرہ کی حرمت ثابت ہو جاتی ہے اور آیت مذکورہ میں دَخَلْتُم بِهِنَّ"
کی شرط کا تعلق صرف " ربائب" کے ساتھ ہے اُمَّعْتُ نِسَائِكُمْ کے ساتھ نہیں.جمہور کی اِس دلیل کی تائید عمرو بن شعیب بنے کی روایت سے بھی ہوتی ہے جو انہوں نے اپنے باپ
کی وساطت سے اپنے دادا سے کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا.اگر کوئی شخص ایک عورت سے نکاح کرے تو اس کے بعد اس کے ساتھ مجامعت کرے
یا نہ کرے اس شخص پر اس عورت کی ماں حرام ہو جاتی ہے.اس روایت کے اصل الفاظ یہ ہیں :-
عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَدِهِ انَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ أَيُّهَا رَجُل كَلَّمَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا أَوْلَمْ يَدْخُلُ فَلَا تَحِلُّ لَهُ
امها له
مشهور صحابی حضرت زید بن ثابت نہ نے بھی اسی مسلک کی صحت کو ثابت کیا ہے.اس روایت
کے الفاظ یہ ہیں :-
سُئِلَ زَيْدُ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ فَا رَقَهَا قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا
هَلْ تَحِلُّ لَهُ اُمَّهَا فَقَالَ زَيْدُ بن ثَابِتٍ لَا الْاتُ مُبْهَمَةٌ لَيْسَ فِيْهَا شَرْطُ
له سورة النساء آیت ۲۴
له سورة النساء آیت ۲۴
س بداية المجتهد كتاب النكاح الفصل الثاني في المصاهرة جلد ۲ ص :
Page 34
I
وَإِنَّمَا الشَّرْطُ فِي الرَّبَائِبِ - له
یعنی حضرت زید بن ثابت سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی شخص کسی عورت سے شادی کرے
اور پھر رخصتانہ سے پہلے اسے طلاق دے دے تو کیا وہ شخص اس عورت کی ماں سے
نکاح کر سکتا ہے.حضرت زید نے اس کا یہ جواب دیا کہ قرآن کریم نے اُمَّهُتُكُمْ ہیں
ام کو عام رکھا ہے اور یہ نہیں فرمایا کہ تمہاری اس بیوی کی ماں جس سے تم مباشرت کر چکے
ہو.اس لئے بیوی کی ماں سے نکاح حرام ہونے کے لئے مباشرت شرط نہیں صرف نکاح
شرط ہے.البتہ بیوی کی بیٹی جو اس کے دوسرے خاوند سے ہے اس کے حرام ہونے
کے لئے مباشرت کی شرط ہے.اگر مباشرت نہیں ہوئی اور طلاق ہوگئی ہے تو اس بیوی
کی لڑکی یعنی ربیبہ سے طلاق دینے والا نکاح کر سکتا ہے.بیٹے ، پوتے اور نواسے کی بیوی وغیرہ سے نکاح ابدی حرام ہے اور نص صریح سے ثابت
ہے جیسا کہ فرمایا :-
وَحَلائِلُ ابْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَا بِكُمْ لَه
یعنی تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری نسل سے ہیں وہ بھی تم پر حرام ہیں.بیٹے کے
ساتھ پوتے اور نواسے کی بیویاں بھی اسی حکم میں شامل ہیں.اس حرمت کے لئے بھی
مباشرت اور مجامعت کی شرط نہیں محض بیٹے کے نکاح سے ہی یہ حرمت واقع ہو جاتی
ہے.ج : " من اصلا یکم کی قید سے یہ واضح ہے کہ متبنی " یعنی منہ بولا بیٹے کی بیوی اس حرمت
کے حکم میں شامل نہیں اس سے نکاح ہو سکتا ہے.چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :-
فلما قضى زَيْدُ مِنْهَا وَطَرًا زَوَجْنَتَهَا لِكَى لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي
ازواجِ ادْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَراً وَكَانَ أَمْرُ اللهِ مَفْعُولاً سه
یعنی جب زید نے اس عورت کے بارہ میں اپنی خواہش پوری کر لی یعنی طلاق دے دی
تو ہم نے اس عورت
کا تجھ سے بیاہ کر دیا تا کہ مومنوں کے دلوں میں اپنے لے پالکوں
ے موطا امام مالک کتاب النکاح باب ما لا يجوز من نكاح الرجل ص ١٩
له سورة النساء آیت ۲۴
سے سورۃ الاحزاب آیت ۳۸
Page 35
کی بیویوں سے جن کو طلاق مل گئی ہے نکاح کرنے کے متعلق کوئی خلش نہ رہے اور خدا
کا فیصلہ ہر حال پورا ہو کر رہنا تھا.د : - کسی مرد کا اپنی بیوی کی بیٹی یعنی ربیہ سے نکاح ابدی حرام ہے.رہلیہ سے مراد مدخولہ بیوی
کے پہلے خاوند کی ایسی لڑکی ہے جس نے اس کے گھر میں اور اس کی سرپرستی میں پرورش پائی ہو.ربیبہ کی حرمت بھی نص صریح سے ثابت ہے جیسا کہ فرمایا :-
"
وَرَبابكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ له
یعنی تمہاری وہ سوتیلی لڑکیاں جو تمہاری ان بیویوں سے ہوں جن سے تم خلوت کر چکے ہو
اور تمہارے گھروں میں پلی ہوں تم پر حرام کی گئی ہیں.اس بارہ میں کوئی اختلاف نہیں کہ رنبیہ کی حرمت کے لئے بیوی یعنی ربیہ کی ماں سے مباشرت او
مجامعت ضروری ہے.اگر بیوی سے مباشرت نہ ہوئی ہو اور علیحدگی ہو گئی تو ایسی بیوی کے پہلے خاوند
کی لڑکی سے نکاح حرام نہیں ہے البتہ فقہاء نے اس بارے میں اختلاف کیا ہے کہ آیا بیوی کے پہلے
خاوند کی بیٹی کا دوسرے خاوند کے گھر میں پرورش پانا بھی اس حرمت کے لئے شرط ہے یا نہیں کیونکہ
آیت مذکورہ بالا میں رہائی کے متعلق " في حُجُورِكُم" کا لفظ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ
مدخولہ عورتوں کی وہ بیٹیاں مراد ہیں جو دوسرے خاوندوں کے گھروں میں پرورش پا رہی ہوں.جمهور فقہاء کا مسلک یہ ہے کہ اہلیہ سے نکاح ہر حال میں حرام ہو گا خواہ اس نے اپنے سوتیلے
باپ کے گھر پرورش پائی ہو یا نہ پائی ہو.احمد یہ مسلک جمہور فقہاء کے مطابق ہے یعنی ربیبہ کا دوسرے خاوند کے گھر میں پرورش پانا اس کی
حرمت کے لئے شرط نہیں ہے.اس مسلک کی تائید اس بات سے ہوتی ہے کہ اگر رہائب کا خاوندوں کے
گھر میں پلنا شرط ہوتا تو آیت میں جہاں یہ کہا گیا ہے کہ خان لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
وہاں یہ الفاظ بھی ہوتے وَ إِن لَمْ تَكُن فِي حُجُورِكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُم پس معلوم ہوا کہ اس آیت میں
حرمت کے لئے صرت " دخَلْتُمْ بِهِنَّ" بطور شرط ہے " في حُجُورِكُم ، بطور شرط نہیں ہے بلکہ بطور واقعہ
اس کا ذکر ہے کہ عموماً ایسا ہوتا ہے.سورة النساء آیت ۲۴
Page 36
سمسم
ابدی محترمات ( بر بنائے رضاعت)
:.وہ رشتے جو بر بنائے نسب حرام ہیں اگر وہی رشتے بر بنائے رضاعت قائم ہوں تو ان سے بھی
نکاح ابدی حرام ہے.مثلاً رضاعی ماں، رضاعی بہن ، رضاعی نواسی ، رضاعی ہوتی ، رضاعی بیٹی، رضاعی خالہ
رضاعی پھوپھی وغیرہ.البتہ حرمت بر بنائے رضاعت صرف دودھ پینے والے تک محدود رہتی ہے اسکے
بہن بھائی اس سے متاثر نہیں ہوتے.رضاعی رشتوں میں رضاعی ماں اور رضاعی بہنوں کی حرمت نص صریح
کی بناء پر ہے جیسا کہ فرمایا :-
وامهتكم التي اَرْضَعْنَكُمْ وَآخَوتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ
یعنی تمہاری وہ مائیں بھی تم پر حرام ہیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے اور تمہاری رضاعی
بہنیں بھی.باقی رضاعی رشتوں کی حرمت نقض حدیث پر مبنی ہے جن کا ذکر شق "ب" میں آئے گا.حرمت رضاعت محض ایک دو مرتبہ دودھ چوس لینے سے واقع نہیں ہوتی.حضرت عائشہ سے مروی
ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-
لا تُحَرِّمُ المَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ أَوِ التَّضْعَةُ وَالرَّضْعَتَانِ له
یعنی ایک دو گھونٹ یا ایک دو مرتبہ دودھ پینے سے حرمت ثابت نہیں ہوتی." رطعة" در اصل ایک مرتبہ سیر ہو کہ دودھ پینے کو کہتے ہیں اور بچہ اوسطاً دن میں پانچ مرتبہ
دُودھ پیتا ہے اور ایک حدیث سے ثابت ہے کہ پانچ بار دودھ پینے سے حرمت رضاعت قائم ہوتی ہے
پس اگر کوئی بچہ کم از کم پانچ مرتبہ سیر ہو کر دودھ پیئے خواہ مختلف اوقات میں تو اس سے حرمت ثابت ہو
جائے گی اس سے کم پر نہیں.روایت کے الفاظ یہ ہیں :-
قَالَتْ عَائِشَةُ أَنْزِلَ فِي الْقُرْآنِ عَشَرُ رَضْعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ فَنَسَعَ مِنْ ذَلِكَ خَمْسَاوَ
صَارَ إلى خَمْسِ رَضْعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ - کے
ل سورة النساء آیت ۲۴
ه ابن ماجه باب لا تحترم المصة والمقتان ص و ابوداؤد صدا و ترمذی ص
له - ترمذی ابواب الرضاع باب لا تحرم المصة الخ.
Page 37
سوم سر
یعنی پہلے دن بار دودھ پینے سے حرمت قائم ہونے کا حکم تھا پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا اور پانچ
بار دودھ پینے سے حرمت ثابت ہونے کا قانون مقرر ہوا.اکثر ائمہ کا اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ رضاعت کی عمر یعنی دو سال کی عمر کے اندر اندر دُودھ
پینے سے حرمت ثابت ہوتی ہے.امام مالک، امام ابوحنیفہ اور امام شافعی کا یہی مسلک ہے.آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رضاعت مجاعت سے ہوتی ہے اور مجاعت اس بھوک
کو کہتے ہیں جو دم بنات
کی عمر کے اندر بچہ دودھ کے لئے محسوس کرتا ہے.روایت کے الفاظ یہ ہیں :.اِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ له
یعنی رضاعت اس عمر میں دودھ پینے کا نام ہے جبکہ بچہ کی بھوک دُور کرنے کا زیادہ تر انصا
دُودھ کی خوراک پر ہو.ایک اور روایت کے الفاظ یہ ہیں :-
لَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ فِي الشَّدي وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ له
یعنی دودھ پینے سے حرمت اس وقت قائم ہوتی ہے جبکہ دودھ سے بچہ پیٹ بھرے.یعنی دودھ اس کی خوراک ہو اور دودھ چھڑانے کی عمر سے پہلے اس نے کسی دوسری عورت
اور
کا دودھ پیا ہو.اس بارہ میں صاحب بدایۃ المجتہد علامہ ابن رشد لکھتے ہیں :.اتَّفَقُوا عَلَى اَنَّ الرَّضَاعَ يَحْرُمُ فِى الْحَوْلَينِ وَاخْتُلِفَ فِي رِضَاعِ الْكَبِيرِ
فَقَالَ مَالِكُ وَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِي وَكَانَةُ الْفُقَهَاءِ لَا يَحْرُمُ رِضَاعُ الكَبير
یعنی علماء کا اِس بات پر اتفاق ہے کہ بچہ اگر دو سال کی عمر میں دودھ پیئے تو رضاعت
ثابت ہوگی اور بڑی عمر کا بچہ اگر دودھ پئے تو رضاعت ثابت نہیں ہوگی.امام مالک :
22
امام ابو ظیفہ، امام شافعی اور اکثر فقہاء کا یہی مسلک ہے.پس فقہاء کی ان تصریحات اور مبینہ روایات کی بناء پر فقہ احمدیہ کا مسلک یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ رضاعت
۲۸۱
له ابوداؤد باب في رضاعة الكبير ص
له ترمذى كتاب الرضاع باب ان الرضاعة لا تحرم الا في الصغر ص
سے بداية المجتهد كتاب النكاح الفصل الثالث في مانع الرضاع منا
Page 38
۳۵
کی عمر کے دوران پانچ مرتبہ پیٹ بھر کہ دودھ پی لے تو حرمت ثابت ہو گی ورنہ نہیں.ب دودھ پینے والے لڑکے یا لڑکی کا رشتہ دُودھ پلانے والی کی اولاد کے علاوہ اس کے یا
اس کے خاوند کے دوسرے رشتہ داروں سے بھی نہیں ہو سکتا.رضاعی ماں اور بہن کے علاوہ دیگر رضاعی رشتوں کی حرمت حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی بناء پر ہے.حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-
يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ له
یعنی دودھ پینے والے پر رضاعت کی وجہ سے وہ تمام رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب کی
وجہ سے ہوتے ہیں.حضرت عائشہ فرماتی ہیں "ابو واقعی" کے بھائی " افلح" آیت حجاب نازل ہونے کے بعد میرے
پاس آئے اور اندر آنے کی اجازت چاہی لیکن میں نے انہیں اجازت نہ دی.بعد میں میں نے اس کے
متعلق حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا وہ تمہارا چا ہے کیونکہ وہ
تمہارے رضاعی باپ ابو العیس کا بھائی ہے اس لئے اسے آنے کی اجازت دے دو.میں نے عرض کی
یا رسول اللہ مجھے دودھ تو ایک عورت نے پلایا ہے مرد نے نہیں پلایا.تو آپ نے فرمایا، نہیں وہ تمہارا
چچا ہے اور تمہارے پاس آسکتا ہے.لہ
لعان
جس عورت سے اُس کے خاوند نے لعان کیا ہو اور اس وجہ سے اُن دونوں میں جدائی ہو گئی
ہو تو وہ عورت اور مرد آئندہ کبھی آپس میں نکاح نہیں کر سکتے تاہم بعض فقہاء نے لعان کو وقتی مانع
قرار دیا ہے.سے
وقتی محرمات
ایسی عورتیں جن سے نکاح کیسی شرعی روک کی وجہ سے جائز نہ ہو اور روک دُور ہو جانے پر نکاح
له ابن ماجه کكتاب النكاح باب ما يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب م١٣٩
کے ابوداؤد كتاب النكاح باب في لبن الفعل ما
ا
له نيل الأوطار باب لا يجتمع المتلاعنان ابدا ما
Page 39
۳۶
جائز ہو جائے " وقتی محرمات “ کہلاتی ہیں اور اس کی مندرجہ ذیل صورتیں ہیں :-
دو بہنوں سے ایک ہی وقت میں نکاح -
دو بہنوں کو بیک وقت نکاح میں جمع کرنا افقی صریح کی رو سے حرام ہے جیسا کہ فرمایا :-
و ان تجمَعُوا بَيْنَ الاختن - ل
یعنی تمہارے لئے حرام ہے کہ دو بہنوں کو بیک وقت اپنی بیوی بنا کر رکھو.دو بہنوں سے اگر ایک ہی ساتھ نکاح کیا جائے تو دونوں نکاح باطل ہوں گے ، لیکن اگر
یکے بعد دیگرے نکاح کرنے سے دو بہنیں اکٹھی ہو جائیں تو پہلا نکاح صحیح ہوگا اور دوسرا باطل.کیونکہ دوسرا نکاح نا درست ہوا ہے.عدت کے دوران بھی معتدہ بیوی کی بہن سے نکاح جائز
نہیں.اگر لاعلمی سے ایک بہن کی موجودگی میں دوسری بہن سے نکاح ہو جائے تو وہ نکاح فاشد
کے حکم میں ہے اور دوسری بہن کی تفریق لازمی ہے.ب - ایک مرد کے نکاح میں بیک وقت ایسی دو عورتیں جمع نہیں ہو سکتیں جو آپس میں خالہ
بھا نجی یا پھو بھی جنہیمی ہوں.خالہ بھانجی اور پھوپھی تیجی کو ایک مرد کے نکاح میں جمع کرنے کی حرمت نفق حدیث پر معنی
ہے.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ " کوئی شخص اپنے عقد میں کیسی عورت کو اس کی پھوپھی
کے ساتھ یا کسی عورت کو اس کی خالہ کے ساتھ جمع نہ کرے " حدیث کے الفاظ یہ ہیں :-
نَهى أن تُزَوَّجَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا له
حضرت ابن عباس کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حرمت کی علمت قطع رحمی ہے کیونکہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-
فَاتَكُمْ إِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ فَقَدْ قَطَعْتُمْ أَرْحَامَكُمْ کے
یعنی اگر تم نے پھوپھی بھتیجی یا خالہ بھانجی کو ایک ساتھ نکاح میں رکھا تو تم قطع رحمی کے گناہ
سورة النساء آیت ۲۴
نکاح فاسد کے لئے دیکھیں دفعہ نمبر ۱۷۱۴
ترمذی کتاب النكاح باب لا تنكح المراة على عمتها او على خالتها.کے طبراني من حديث ابن عباس" بحواله نصب الراية صال
Page 40
۳۷
کے مرتکب ہو گے.ظاہر ہے کہ اس ممانعت سے شارع کا منشاء صلہ رحمی اور ایسی قریبی رشتہ داری میں موقت
و محبت کو فروغ دینا اور قطع رحمی کے حالات سے بچانا ہے.ج : منکوحہ غیر سے نکاح جائز نہیں جب کہ اس کا پہلا نکاح قائم ہو.یہ حرمت بھی نص صریح کی
بناء پر ہے جیسا کہ فرمایا :-
وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ النِّسَاءِ
یعنی پہلے سے منکوحہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں.آیت مذکورہ بالا کے آغاز میں حرمت علیکم" کے الفاظ ہیں جو دَ المُحْصَنَتُ مِنَ النِّسَاءِ
جودَ
پر بھی حاوی ہیں.پس کسی منکوحہ عورت سے نکاح نقص صریح کی بناء پر حرام ہے.اگر عدم علم کی وجہ سے ایسا نکاح
ہو جائے اور فریقین میں مباشرت بھی ہو جائے تو یہ وطی با شبہ کے حکم میں ہو گا اور علم ہوتے ہی تفریق
لازم آئے گی.دیگر معاملات یعنی حق مہر، نسب وغیرہ نکاح فاسد کے حکم میں ہوں گے.لے
:- چار بیویوں کی موجودگی میں پانچواں نکاح جائز نہیں.یہ حرمت قرآن شریف کی اس
آیت سے ثابت ہے :-
فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنى وَثُلَثَ وَرُبع فَإِنْ خِفْتُمْ الَّا تَعْدِلُوا
فَوَاحِدَةً له
یعنی تم اپنی پسند کے مطابق دو دو تین تین چار چار عورتوں سے شادی کر سکتے ہو اور اگر
تمہیں ڈر ہو کہ تم عدل سے کام نہیں لے سکوگے تو پھر ایک عورت سے ہی شادی کرو.حرمت کا یہ حکم آیت مذکورہ سے دلیل خطاب کے تحت نکلتا ہے اور اس کی تائید حدیث شریف
سے ہوتی ہے.ترندی کی روایت ہے کہ غیلان بن سلمہ النقضی نے جب اسلام قبول کیا تو ان کے عقد میں
دس بیویاں تھیں ان بیویوں نے بھی ان کے ساتھ اسلام قبول کر لیا.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو
اختیار دیا کہ وہ ان میں سے چار بیویاں رکھ کر باقی کو الگ کر دیں.سکے
لے مزید تفصیل کے لئے دیکھیں دفعہ نمبر ۴ ، نمبر ۱۷ نکاح فاسد و ثبوت نسب : ٢ سورة النساء آیت ۴
ترمذى كتاب النکاح باب في الرجل يسلم وعنده عشر نسوة ما
Page 41
غرض قرآن کریم کی آیت مذکورہ اور حدیث شریف سے یہی ثابت ہے کہ چار کی موجودگی میں پانچواں
نکاح جائز نہیں.ھ :.معدہ سے نکاح جائز نہیں.معتدہ ایسی عورت کو کہتے ہیں جو عدت سے گزار رہی ہو.عدت خواہ طلاق کی ہو یا بیوگی کی اور عرصہ
عدت خواہ حیض ہو یا وضع حمل کا یا مہینوں کا کسی صورت میں عدت کے دوران نکاح جائز نہیں جیسا کہ
فرمایا :-
وَلَا تَعزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتُبُ أَجَلَة له
یعنی جب تک عدت کا حکم اپنی میعاد کو نہ پہنچ جائے اس وقت تک تم نکاح باندھنے کا پختہ
ارادہ نہ کرو.دار مشرک یا مشترکہ سے نکاح جائز نہیں البتہ کتابیہ عورت سے نکاح جائز ہے.مشرک یا مشرکہ سے نکاح کی حرمت نقق صریح کی بناء پر ہے جیسا کہ فرمایا :-
لا تَنكِحُوا الْمُشْرِكِتِ حَتَّى يُؤْمِنَ، وَلَامَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ
اعجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدُ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ
مشْرِك وَلَوْ اعْجَبكُم له
یعنی تم مشرک عورتوں سے جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں نکاح نہ کرو اور ایک مومن
لونڈی ایک مشرک عورت سے خواہ وہ تمہیں کتنی ہی پسند ہو یقینا بہتر ہے اور مشرکوں
سے جبہ ایک وہ ایمان نہ لے آئیں مسلمان عورتیں مت بیا ہو اور ایک مومن غلام ایک
مشرک آزاد سے خواہ وہ تمہیں کتنا ہی پسند ہو یقینا بہتر ہے.مشرکہ سے نکاح بھی ثبوت نسب کی حد تک نکاح فاسد کے حکم میں ہے.یہ نکاح باطل اور کالعدم
ہے اور اگر یہ مشرکہ ایمان لے آئے تو پھر نیا نکاح ضروری ہوگا.ز :- مطلقہ بستہ اپنے سابق خاوند سے نکاح نہیں کر سکتی یعنی جس نے اسے طلاق بتہ دی ہے.عدت کی تفصیل کے لئے دیکھیں دفعہ نمبر ۴۸
له سورة البقره آیت ۲۳۶
سے سورۃ البقرہ آیت ۲۲۲
Page 42
۳۹
جس عورت کو مخصوص طریق کے مطابق الگ الگ وقتوں میں وقفہ وقفہ کے بعد تین طلاقیں اسکے
خاوند نے دی ہوں تو دوبارہ وہ آپس میں نکاح نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ وہ عورت کسی اور شخص
سے شادی کرے اور پھر کسی طبعی یا قدرتی وجہ سے اس سے علیحدگی ہو جائے تو اس طرح حتی تنکح
زوجا خيره " یعنی نکاح ثانی کی شرط پوری ہو جانے کی وجہ سے وہ اپنے اس خاوند سے بھی نکاح کرسکتی
ہے جس نے اسے طلاق بتہ دی تھی یکے
شرط نمبر ۲ : صحت نکاح کے لئے دوسری شرط یہ ہے کہ عورت اور اس کا ولی دونوں اس نکاح پر
راضی ہوں.تشریح الف : شرعی نکاح کے لئے ضروری ہے کہ نہ صرف عورت خود نکاح کے لئے راضی ہو بلکہ
اس کا ولی بھی نکاح پر رضامند ہو.نہ تو محض ولی کی رضامندی سے نکاح ہو سکتا ہے اور نہ صرف عورت
کی رضا مندی سے.اگر لڑکی نابالغ ہے تو اس کی رضامندی اس کے بالغ ہونے تک معلق رہتی ہے جب وہ خود
بالغ ہو جائے تو وہ اپنے خیار بلوغ کا حق استعمال کرتے ہوئے نابالغی کا یہ نکاح قائم بھی رکھ سکتی ہے
اور مسترد بھی کر سکتی ہے.فقہ احمدیہ کی رُو سے لڑکی خواہ بالغ ہو یا نا بالغ باکرہ ہو یا شیبہ اس کا نکاح ولی کی رضا مندی
کے بغیر درست نہیں کیونکہ صحت نکاح کے لئے جہاں عورت کی اپنی رضامندی ضروری ہے وہاں ولی کی
رضا مندی بھی لازمی ہے.فقہ احمدیہ کا یہ مسلک ارشادات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفائے راشدین کے
تعامل پر مبنی ہے.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور خلفائے راشدین کے چند حوالے درج ذیل ہیں :-
حضرت ابو بردہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں لا نكاح إلا بولی یعنی عورت کا نکاح ولی کی
اجازت کے بغیر نہیں ہوتا.یہ روایت مختلف سندات سے مروی ہے جو صحیح اور ثابت ہیں کہ
ے تفصیل کے لئے دیکھیں دفعہ نمبر ۳۵ طلاق بتہ : سورة البقره آیت ۲۳۱
نیز اسکی تشریح کی جو میچ کے ابوداؤد کتاب النکاح باب في الولى جلد اول ما
"
"
44
۱۳۵
۲۸۴
ترمذى كتاب النكاح باب لا نكاح الا بولى من : ابن ماجه كتاب النكاح باب لا نكاح الا بولى صدا :
Page 43
اسی مضمون کی روایات حضرت علی بن ابی طالب ، حضرت عبد اللہ بن عباس ، حضرت معاذ بن جبل
حضرت عبد اللہ بن عمر، حضرت ابو ذر غفاری نے حضرت عبد اللہ بن مسعود اور حضرت انس بن مالک سے بھی
مروی ہیں.لے
اسی طرح امہات المؤمنین میں سے حضرت عائشه نم حضرت ام سلیم اور حضرت زینب بنت جحش
سے بھی صحیح سند کے ساتھ اس مضمون کی روایات موجود ہیں.سے
حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی عورت ولی کی اجازت
کے بغیر نکاح کرے تو اس کا نکاح باطل ہے.حدیث کے الفاظ یہ ہیں :-
أيُّهَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ اِذْنِ وَلِيْهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلُ فَنِكَاحُهَا بَاطِك
فَيْكا حُهَا بَاطِل
اسی طرح حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-
لا تُزَوّجُ المَرأَة نَفْسَهَا فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسُهَا له
یعنی کوئی عورت بغیر ولی کے خود اپنا نکاح نہ کروائے اور جو عورت بغیر ولی کے خود کوکسی
کی زوجیت میں دے دے تو وہ گویا زانیہ ہے.حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں :-
لا نكَاحَ إِلَّا بِوَلِي وَشَاهِدَى عَدْلٍ له
یعنی کسی عورت کا نکاح ولی کی اجازت اور دو عادل گواہوں کے بغیر درست نہیں.خلفائے راشدین ان کا تعامل بھی اس مسلک کی تائید کرتا ہے حضرت عمر اور حضرت علی نے اپنے عہد خلافت
میں اس مسلک کو درست سمجھا اور اس پر سختی سے عمل کر دیا اور اعلان کیا کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح درست
نہیں ہوگا.له نيل الأوطار كتاب النکاح باب لا نكاح الا بولى صلال الاول
اولا
سے ترمذی کتاب النکاح باب لا نكاح الا بولى جلد اول ص ٣
که دار قطني كتاب النكاح جلد ۲ ص
Page 44
ایک دفعہ ایک عورت نے اپنے جائز ولی کی بجائے کیسی دوسرے شخص کو اپنا ولی بنا کر نکاح کر لیا.جب
حضرت عمر کے پاس یہ خبر پہنچی تو آپ نے نکاح کرنا جائز قرار دیا اور ولی بننے والے اور نکاح کرنے والے ونوں
کو کوڑے لگوائے.روایت کے الفاظ یہ ہیں :-
عنْ عِكْرَمَةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ جَمَعَتِ الطَّرِيقُ رَكْبًا فَجَعَلَتْ اِمْرَأَةٌ مِنْهُمُ
تب أمْرَهَا بِيَدِ رَجُلٍ غَيْرَ وَلِي فَانْكَحَهَا فَبَلَغَ ذلِكَ عُمَرَ فَجَلَدَ النَّالِعَ
وَالْمُنْكِحَ وَرَدُّ نِكَا حَهَا.له
اسی طرح حضرت علی بھی اِس بارہ میں سختی فرمایا کرتے تھے اور ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرنیوالے
کو کوڑے لگوایا کرتے تھے.روایت کے الفاظ یہ ہیں :-
ما كانَ اَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَدَّ فِي النِّكَاحِ
بِخَيْرٍ وَلِي مِنْ عَلَقٍ وَكَانَ يَضْرِبُ فِيهِ - لَهُ
ب : استحقاق ولایت نکاح
ولایت کا حق کیسے ہے اس لحاظ سے سب سے مقدم ولی عورت کا باپ ہے اس کے بعد علی الترتیب
دادا، سگا بھائی، سوتیلا بھائی، چچا وغیرہ قریبی عصبات عورت کے نکاح کے لئے ولی ہو سکتے ہیں.نکاح کی ولایت کا مندرجہ بالا حق رشتہ داروں میں اقر بیت کی بنیاد پر جتنا کوئی رشتہ دار نہ یادہ
قریبی ہوگا اسی نسبت سے اسے حق ولایت حاصل ہوگا.قریبی ولی کی موجودگی میں دور کے ولی کا حق ولایت مؤثر نہیں ہوگا تا ہم سب بھائی حق ولایت میں
یکساں ہیں ان میں سے کوئی بھی عاقل بالغ بھائی بہن کے نکاح کے لئے ولی بن سکتا ہے عمر کا فرق موثر نہیں
ہوگا.ج :.فقہ احمدیہ کی رو سے ولی کے مفہوم میں عمومیت ہے جری قریبی رشتہ دار بھی ولی ہے
اور جماعت احمدیہ کے امام کو بھی ولایت عامہ حاصل ہے.پس اگر کسی عورت کا کوئی قریبی جدی رشتہ دار
ولی نہ ہو یا انصاف سے کام نہ لے اور اس حق کے استعمال میں لڑکی کا مفاد اس کے مد نظر نہ ہو اور
لڑکی پر جبر کر رہا ہو تو لڑکی یا اس کے وکیل مجاز کی درخواست پر امام جماعت نحو دیا اس غرض کے لئے
ه دار قطني كتاب النكاح.۳۸۳
۳۸۵
"
Page 45
۴۲
ان کا مقرر کردہ نمائندہ کسی اور مناسب آدمی کو ولی نکاح مقرر کر سکتا ہے جو لڑکی کی رضامندی اور اسکے
مفاد کے مطابق یہ فریضہ انجام دے گا اور اس کی یہ کارروائی درست اور معتبر ہوگی.عام حالات میں عورت نکاح کی ولی نہیں بن سکتی.مثلا ماں، دادی، نانی ، بہن ، پھوپھی وغیرہ
ولی نکاح نہیں ہوں گی.ایک دفعہ حضرت عائشہؓ نے اپنے خاندان کے ایک لڑکے اور لڑکی کے نکاح کی بات طے کی.جب دیگر امور طے پاگئے تو آپ نے خاندان کے ایک شخص کو کہا کہ وہ اس نکاح کی بحیثیت ولی اجازت
دے کیونکہ عورتوں کو نکاح کی ولایت کا اختیار نہیں ہے.لے
شرط نمبر ۳ دو گواہوں کا ہونا
صحت نکاح کے لئے کم از کم دو گواہان کا ہونا ضروری ہے.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ بغیر گواہوں کے نکاح نہیں ہوتا.حدیث کے الفاظ یہ ہیں :-
تشریح : : عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ۖ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا
نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِي وَشَاهِدَى عَدْلٍ له
ب : - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا بُدَّ
فِى النِّكَاحِ مِنْ اَرْبَعَةِ الْوَلِي وَالزَّوْجِ وَالشَّاهِدَيْنِ - له
حضرت عائشہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِي وَشَاهِدَى عَدْلٍ وَمَا كَانَ مِنْ نِكَاحِ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ بَاطِل
یعنی کوئی نکاح ولی کی رضا مندی اور دو عادل گواہوں کے بغیر درست نہیں ہوتا اور
جو نکاح اس کے بغیر ہو وہ باطل ہے.گواہوں کے لئے عاقل بالغ ہونا ضروری ہے.مرد گواہ رکھے جائیں بشرط ضرورت ایک مرد اور
ه محلی ابن حزم جلد ۱ ص۴۵۳
له دار قطني كتاب النكاح ص٣٨
تے
144
اخرجه ابن حبان في صحيحه بحواله نصب الرايه صين
Page 46
۴۳
دو عورتیں بھی انعقاد نکاح کے گواہ بن سکتے ہیں.جس شخص سے بوقت ضرورت سچی گواہی کی توقع نہ ہو اس کو گواہ بنانا بیکار ہے.ه
دفعہ نمبر 4
مہر اُس مالی منفعت کا نام ہے جو نکاح کے نتیجہ میں خاوند کی طرف سے
بیوی کو واجب الادا ہے اور جس پر بیوی کلی تصرف کا حق رکھتی ہے.تشریح نکاح کی صحت کے لئے پہلے سے حق مہر مقر کرنا ضروری نہیں جیسا کہ قرآن کریم کی اس
آیت سے ظاہر ہے :-
لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَهُ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا
d
لَهُنَّ فَرِيضَةً له
یعنی تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم عورتوں کو اس وقت بھی طلاق دے دو جبکہ تم نے ان کو چھوا
تک نہ ہو یا مہر نہ مقرر کیا ہو.البتہ رخصتی ہو جانے کے بعد پورا حق مہر خود بخود واجب ہو جاتا ہے اور اگر حق مہر متعین نہ ہو
تو مہر مثل کی ادائیگی واجب ہوتی ہے خواہ نکاح کے وقت مہر کا ذکر آیا ہو یا نہ آیا ہو.اس لحاظ سے یہ کہا
جا سکتا ہے کہ کوئی نکاح بغیر حق مہرا کے نہیں.حق مہر کی ادائیگی خاوند کے ذمہ واجب ہے جیسا کہ فرمایا :-
له سورة البقره آیت ۲۳۷
Page 47
۴۴
وأتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً له
یعنی عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی کے ساتھ ادا کرو.مهر بیوی کا حق ہے وہی اس کی مالک ہے وہ جس طرح چاہیے اسے اپنے مصرف میں لا سکتی ہے
خاوند کی وفات پر اگر مہر واجب الادا ہو تو دیگر قرضوں کی طرح حق مہر کی ادائیگی بھی خاوند کے ترکہ سے
لازمی ہے.دفعہ نمبر را
مهریتی
وہ مہر ہے جو فریقین کی رضا مندی سے بوقت نکاح کے پایا جائے اور اعلان
نکاح میں اس کا ذکر آجائے.تشریح جو حق مہر وقت نکاح مقر کیا جائے اور اعلان نکاح میں اس کا ذکر آئے موسیٹی کہلاتا
ہے.ادائیگی کے لحاظ سے مہر سمتی کی رواجا دو قسمیں بیان کی گئی ہیں..مهم معجل
ب : مهر موقبل
ا : میر مجمل مقررہ مہر کا وہ حصہ ہے جو بوقت نکاح فوری طور پر ادا کر دیا جائے یا بیوی کے
مطالبہ پر عند الطلب ادا کر نا تسلیم کیا جائے یا معاہدہ نکاح میں مہر کی ادائیگی کے وقت کا کوئی ذکر نہ ہو.ایسے مہر کی عدم ادائیگی کی صورت میں بیوی خاوند کو اپنے نفس پر قدرت دینے سے انکار کرسکتی ہے اور
لے سورة النساء آیت ۵
Page 48
۴۵
عورت کے مطالبہ پر قضاء فوری ادائیگی پر خاوند کو مجبور کرسکتی ہے.به مهر موقبل مقررہ مہر کا وہ حصہ ہے جو زوجین کی علیحدگی یا خاوند کی وفات کے بعد قابل ادا
ہو جیسا کہ ذکر آچکا ہے.مہر ایک قرضہ ہے جو خاوند کے ترکہ میں سے اس کے دیگر قرضوں کی طرح ادا ہونا
چاہیے.مر مسمی کے بالمقابل مہر محمول ہے جس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں جیسے کسی مجہول جنس یا نوع کا ذکر
کرنا لیکن اس کی تعین نہ کرنا مثلاً یہ کہا جائے کہ میں حق مہر میں کوئی جانور ، زمین ، مکان یا کار وغیرہ
دوں گا مگر اس کی تعین نہ کی جائے یا اس کی مالیت کی تعیین نہ کی جائے یا اعلان نکاح میں مہر کا ذکر
نہ ہو یا فریقین کے درمیان مہر کی مقدار میں تنازعہ ہو اور ثبوت موجود نہ ہو.ان سب صورتوں میں
اگر باہمی رضامندی سے کوئی بات ملے نہ ہو سکے اور تنازعہ عدالت میں جائے تو مہر مثل واجب الادا ہو گا.دفعہ نمبر
مهر تجل
مہر معجل کی صورت میں بیوی جب چاہے مہر کا مطالبہ کر سکتی ہے.تشریح
چونکہ عورت مہر کی کلیۂ حقدار ہے اور یہ نکاح کے ساتھ ہی خاوند پر واجب ہو جاتا ہے.اس لئے عورت جب چاہے اس کا مطالبہ کر سکتی ہے یہاں تک کہ ائمہ اور فقہاء اس بات پر متفق ہیں
کہ ابتداء جب کہ ابھی تعلقات زوجیت قائم نہ ہوئے ہوں عورت کو اختیار ہے کہ وہ خاوند کوتا ادائیگی
مهر تعلقات زوجیت قائم کرنے سے روک دے.اگر تعلقات زوجیت قائم ہو چکے ہوں تو اس صورت
ے مہر مثل کی تشریح کے لئے دیکھیں دفعہ نمبر ۱۲
Page 49
3
میں بھی امام ابو حنیفہ کے نزدیک عورت کا یہ اختیار باقی رہتا ہے کہ وہ کسی وقت بھی تا ادائیگی مرحقوق زوجیت
ادا کرنے سے انکار کر دے.اگر رخصتانہ سے قبل طلاق دے دی جائے تو عورت نصف مہر مقررہ کی حقدار ہوگی جیسا کہ فرمایا
اِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً
فَنَصُفُ مَا فَرَضْتُمْ له
یعنی اگر تم انہیں قبل اس کے کہ تم نے انہیں چھوڑا ہو لیکن مہر مقرر کر دیا ہو طلاق دیدو
تو اس صورت میں جو مہر تم نے مقرر کیا ہو اس کا آدھا ان کے سپرد کرنا ہوگا.اگر رخصتانہ سے قبل خاوند مر جائے تو عورت پورے مقررہ مہر کی حقدار ہوگی اور وراثت سے
بھی اسے حصہ ملے گا.لہ
اگر نکاح کے وقت مہر مقرر نہ ہوا ہو اور قبل از رخصتا نہ طلاق ہو جائے یا خاوند فوت ہو
جائے تو پھر مہر مثل کا نصف یا پورا مہر مثل ادا کرنا واجب نہیں حسب استطاعت مناسب تحائف دے کر
عورت کو رخصت کیا جا سکتا ہے.اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :-
لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ
فَرِيضَةً ۖ وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ جَمَتَاعًا
بِالْمَعْرُونِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ له
یعنی تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم عورتوں کو اس وقت بھی طلاق دے دو جبکہ تم نے انہیں
چھوا تک نہ ہو یا مہر نہ مقرر کیا ہو.اور چاہیئے کہ اس صورت میں تم انہیں مناسب طور پر
کچھ سامان دے دو.یہ امر دولتمند پر اس کی طاقت کے مطابق لازم ہے اور نا دار پر آسکتی
طاقت کے مطابق.ہم نے ایسا کہ نانیکو کاروں پر واجب کر دیا ہے.له سورة البقره آیت ۲۳۸
له الاحوال الشخصيه على المذاهب الخمسه ص كتاب الفقه على المذاهب الاربعه من
ه سورة البقره آیت ۲۳۷
Page 50
۴۷
معاہدہ نکاح میں مہر کی عدم تعیین کی صورت میں بوقت تنازعہ قاضی جو مہر
فریقین کی حیثیت کے مطابق متعین کرے وہ مہر
مثل “ ہے.تشریح مر مثل در حقیقت فقهاء کی وضع کردہ اصطلاح ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ بوقت نکاح اگر
کیسی عورت
کا مہر مقررنہ ہوا ہو تو قاضی عورت اور مرد کے حالات
کو دیکھ کر جو مر مقرر کرے وہ مہر مثل
کہلاتا ہے، صاحب ہدایہ مہر مثل کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں :.مہر مثل کی تعیین کے لئے یہ دیکھنا بھی ضروری ہے کہ حسن و جمال، سیرت و کر دار اور علم و عمل کے لحاظ
سے اس عورت کی جو رشتہ دار عورتیں اس کے ہم یا یہ ہیں ان کا مہر کتنا مقررہ ہوا تھا.اس جائزہ میں عورت کے باپ کی طرف سے رشتہ دار عورتوں کو مد نظر ر کھا جائے گا مثلاً بہنیں،
پھوپھیاں اور چا زاد بہنیں وغیرہ ماں کی طرف سے رشتہ دار عورتیں مثلاً خالائیں ، خالہ زاد بہنیں وغیرہ کو
اس جائزہ میں مد نظر نہیں رکھا جاتا ہے
بعض فقہاء کے نزدیک مہر مثل کی تعیین کے لئے عورتوں کے شوہروں کے حسب اور ان کی مالی
استطاعت کو بھی مد نظر رکھا جانا چاہئیے.کے
ہمارے نزدیک تنازعہ کی صورت میں قاضی حالات کا جائزہ لے کر جس مقدار مہر کا فیصلہ کرے گا
وہی مہر مثل ہو گا.جائزہ کے انداز حالات کے لحاظ سے مختلف ہو سکتے ہیں تنازعہ کی بالعموم مندرجہ ذیل
۱۲۸
له كتاب الفقه على المذاهب الاربعة كتاب النكاح مبحث ما يعتبر به مهر مثل ما
هدايه كتاب النكاح من مطبع مجیدی کانپور.له فتح القدير جلد ٢ منم
Page 51
صورتیں ہوسکتی ہیں :.: اگر کوئی مرد اپنا نکاح کرے اور وہ کوئی مہر مقرر نہ کرے اور بعد میں مقدار مہر کے بارہ میں تنازعہ
اُٹھ کھڑا ہو.ب : - کوئی شخص کسی عورت سے اس شرط پر نکاح کرے کہ حق مہر کوئی نہ ہو گا.ج :- مہر محمول مقرر کرے مثلاً نکاح کے وقت جنس یا نوع کا ذکر تو ہو مگر اس کی تعیین نہ ہوئی ہو.مہر میں کوئی ایسی چیز مقرر کی جس کی کوئی مالیت نہیں یا جسے ٹال نہیں کیا جا سکتا.ران سب صورتوں میں نکاح صحیح ہو جائے گا اور مہر لازم ہو گا لیکن نکاح کے بعد اگر مہر کی مقدار
میں تنازعہ ہو تو قاضی کے فیصلہ کے مطابق مہر مثل کی ادائیگی واجب ہوگی.دفعہ نمبر ۱۳
مہر کی مقدار
مہر کی رقم خاوند کی مالی حیثیت کے مطابق ہونی چاہیئے.تشریح
فقہاء سلف نے حق مہر کی زیادہ سے زیادہ کوئی حد مقرر نہیں کی.ان کی تمام تر توجہ
اقل مقدار کی طرف رہی ہے.زمانہ ماضی میں چونکہ رجحان یہ تھا کہ کم سے کم مہر کتنا ہو سکتا ہے اور یہ اس
وجہ سے تھا کہ حق مہر کی اہمیت واضح ہو اور معقولیت کی حد سے کم حق مہر مقرر نہ کیا جائے.چنانچہ اُس
زمانہ کے معیار زندگی کے مطابق یا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے فقراء المهاجرین نے جو حق مہر
کئے تھے ان کی مقدار کو کم از
کم حق مہر قرار دیا گیا اور معیار یہ ٹھرا کہ فقراء المهاجرین نے جو حق مہر باندھے
اس سے کم حق مہر کسی صورت میں نہ ہو.حضرت امام ابوحنیفہ کے نزدیک کم سے کم مقدار مہر دس درہم یا اس کی مساوی مالیت کی کوئی شئے
Page 52
۴۹
ہو سکتی ہے.بر صغیر میں غالباً اسی بناء پر کم سے کم مہر کی مقدار ساڑھے نہیں (۳۲) روپے قرار
دی گئی لیکن فی زمانہ ساڑھے نہیں روپے حق مہر مقرر کرنا ائمہ سلف کے قلیل ترین معیار اور مختلف زمانوں
میں قدر زر کے اختلاف کے لحاظ سے درست معلوم نہیں ہوتا.کیونکہ یہ حق مہر کی اہمیت اور حکمت کے
منافی ہے.المد سلف نے زیادہ سے زیادہ حق مہر کی کوئی حد مقرر نہیں کی کیونکہ یہ اُس زمانے کا مسئلہ نہ
تھا لیکن فی زمانہ یہ رجحان پیدا ہو گیا ہے کہ نمائش یا دباؤ کے پیش نظر بھاری رقوم حق مہر کے طور پر
مقرر کی جائیں اگر چہ نیت اس کی ادائیگی کی نہیں ہوتی حالانکہ شریعیت کا منشاء یہ ہے کہ مہر ادائیگی کی نیت
سے ہی مقرر کیا جائے اور پھر اسے ادا بھی کیا جائے.اس لئے زیادہ حق مہر باندھنے کے غیر صحتمند رجحان کی
روک تھام فی زمانہ لازمی ہے.چنانچہ اس زمانہ کے حکم و عدل حضرت بانی سلسلہ احمدیہ اس بارہ میں فرماتے
ہیں :-
رو
ہمارے ملک میں یہ خرابی ہے کہ نیت اور ہوتی ہے اور محض نمود کیلئے لاکھ لاکھ روپے کا مہر ہوتا
ہے.صرف ڈراوے کے لئے دیکھا جایا کرتا ہے کہ مرد قابو میں رہے.اور اس سے پھر دوسرے نتائج
خراب نکل سکتے ہیں.نہ عورت والوں کی نیت لینے کی ہوتی ہے اور نہ خاوند کے دینے کی.میرا مذہب یہ ہے کہ جب ایسی صورت میں تنازعہ آپڑے تو جب تک اس کی نیت ثابت نہ
ہو کہ ہاں رضا و رغبت سے وہ اسی قدر مہر پر آمادہ تھا جس قدر کہ مقرر شدہ ہے تب تک
مقرر شدہ نہ دلایا جاوے اور اس کی حیثیت اور رواج وغیرہ کو مد نظر رکھ کر پھر فیصلہ کیا
جاوے کیونکہ بدنیتی کی اتباع نہ شریعت کرتی ہے اور نہ قانون کے
بعد ازاں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ حضرت بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ کے اس ارشاد کی روستا ن میں
مہر کی انتہائی حد مقرر کرنے کی ضرورت محسوس کی گئی چنا نچہ سید نا حضرت مصلح موعود ( اللہ آپ سے
راضی ہو ) نے اِس سلسلہ میں فرمایا :
یکس نے مہر کی تعیین چھ ماہ سے ایک سال تک کی آمد کی ہے.یعنی مجھ سے کوئی مہر کے
لے درہم کی قیمت اس زمانہ میں اُس کی قوت خرید کو مد نظر رکھ کہ مقرر ہونی چاہئیے کیونکہ اس وقت ایک
درہم کی ایک بکری یا دو بکریاں ملتی تھیں.بدر جلد نمبر ۱۶ - صفحه ۱۲۳ - ۸ مئی ۶۱۹۰۳
Page 53
متعلق مشورہ کرے تو میں یہ مشورہ دیا کرتا ہوں کہ اپنی چھ ماہ کی آمد سے ایک سال تک کی
آمد بطور مہر مقرر کر دو اور یہ مشورہ میرا اس امر پر مبنی ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود
عليا الصلوة والسلام سے الوصیت کے قوانین میں دسویں حصہ کی شرط رکھوائی ہے.گویا اسے بڑی
قربانی قرار دیا ہے.اس بناء پر میرا خیال ہے کہ اپنی آمدنی کا دسواں حصہ باقی اخراجات
کو پورا کرتے ہوئے مخصوص کر دینا معمولی قربانی نہیں بلکہ سی ٹی قربانی ہے کہ جس کے بدلے
میں ایسے شخص کو جنت کا وعدہ دیا گیا ہے اس حساب سے ایک سال کی آمد جو گویا متواتر
دس سال کی آمد کا دسواں حصہ ہوتا ہے بیوی کے مہر میں مقرر کر دینا مہر کی اغراض کو پورا
کرنے کیلئے بہت کافی ہے بلکہ میرے نزدیک انتہائی حد ہے " لے
پس جماعت احمدیہ کا مسلک یہ ہے کہ حق مہر نہ اتنا کم ہو کہ وہ عورت کے وقار کے منافی محسوس
ہوا اور شریعیت کے ایک اہم حکم سے مذاق بن جائے اور نہ اتنا زیادہ کہ اس کی ادائیگی تکلیف مالا يطاق
ہو جائے.اس اصول کی بناء پر خاوند کی جو بھی مالی حیثیت ہو اس کے مطابق کچھ ماہ سے بارہ ماہ تک کی
آمدنی کے برابر حق مہر کو معقول اور مناسب خیال کیا گیا ہے.دفعہ نمبر ۱۴
نکاح
نکاح اپنے انعقاد اور اثرات کے اعتبار سے صحیح ہوتا ہے یا فاسد یا باطل.تشریح اگر کسی نکاح میں صحت نکاح کی جملہ شرائط پائی جائیں تو نکا ہی ہو گا اور اگر صحت نکات کی
له الفضل ۱۲ دسمبر ۶۱۹۴۰
Page 54
۵۱
شرائط کے لحاظ سے اس میں کوئی ایسا ستم ہو جس کا ازالہ ہو سکتا ہے تو وہ نکاح فاسد کی لائے گا اور جب یہ
ستم دور ہو جائے تو یہی نکاح صحیح ہو جائے گا اور اگر کوئی نکاح بنیادی طور پر حرام ہو یعنی اس کا ستم دور
نہ ہوسکتا ہو تو وہ نکاح باطل ہو گا اور کوئی چیز باطل نکاح کو درست نہیں کر سکتی.نوٹ :.ہر ایک کی تعریف و تفصیل آئندہ دفعات میں ملاحظہ ہو.دفعہ نمبر ۱۵
نکاح صحیح
نکاح صحیح وہ نکاح ہے جو شریعت کے مطابق ہو اور صحت نکاح کی جملہ شرائط
اس میں موجود ہوں.تشریح صحت نکاح کے لئے جیسا کہ قبل ازیں بیان ہو چکا ہے فریقین کی رضامندی، عورت کے ولی
کی رضامندی، دو عاقل بالغ گواہوں کی گواہی حق مہر کا وجوب اور مناسب طریق پر نکاح کا اعلان ضروری
امور ہیں.علاوہ ازیں یہ شرط بھی ہے کہ عورت شرعی موانع سے خالی ہوئی.ان سب شرائط کی پابندی کے
ساتھ جو نکاح ہو گا شریعیت کی رُو سے وہ نکاح صحیح ہوگا.ے دیکھیں دفعہ نمبر د صحت نکاح
ه ان موانع کی تفصیل کے لئے دیکھیں دفعہ نمبر ۸ اور اس کی شرائط شرط نمبرا مع تشریح
Page 55
۵۲
دفعہ نمبر ۱۶
نکاح صحیح کے نقیمہ میں فریقین کو حق مساكنت حق مقاربت حق تو ارث اور حق
ثبوت نسب اور اس قسم کے دوسرے سب معاشرتی حقوق حاصل ہو جاتے
تشریح عمان میں سے تیج میں زوجین کو کچھ حقوق حاصل ہوتے ہیں اور کچھ فرائض ان پر مائے ہوتے
کے نتیجہ عائد
ہیں جیسا کہ فرمایا :.وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُونِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً له
یعنی جس طرح ان عورتوں پر کچھ ذمہ داریاں ہیں ویسے ہی مطابق دستور انہیں کچھ
حقوق بھی حاصل ہیں.ہاں مردوں کو اُن پر ایک طرح کی فوقیت حاصل ہے.فریقین کے حقوق و فرائض..نکاح کے نتیجہ میں جو حقوق دو طرفہ طور پر حاصل ہوتے ہیں وہ حق مساکنت ، حق مقاربت ، حق
ثبوت نسب حق تو ارث اور حرمت مصاہرت ہیں یعنی میاں بیوی دونوں اکٹھے ایک جگہ رہنے کاحق رکھتے
ہیں کیسی دوسرے کو اس پر اعتراض کا حق نہیں اس طرح دونوں حسب حصہ شرعی ایک دوسرے کے ترکہ
میں حقدار ہوں گے.دونوں کے لئے حرمت مصاہرت واقع ہو گی یعنی مصاہرت
کی بناء پر واقع ہونیوالے
ایسے رشتے حرام ہوں گے جن کا ذکر دفعہ نمبر اور اس کی مشروط نمبر کی تشریح میں گذر چکا ہے.بیوی کے حقوق و فرائض
و نکاح صحیح کے نتیجہ میں بیوی مہر کی حقدار ہو جاتی ہے اور خاوند پر اس کی ادائیگی واجب ہے لیئے
ے سورۃ البقرہ آیت ۲۲۹
سے تفصیل کے لئے دیکھیں دفعہ نمبر 4
Page 56
سرك
ب :.بیوی نان و نفقہ کی حقدار ہوتی ہے اور خاوند نان و نفقہ ادا کر نے کا ذمہ دار ہے لیے
ج :.بیوی کو خاوند کے گھر میں رہنے کا حق حاصل ہو جاتا ہے.اس کے مقابل پر بیوی پر یہ
ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ خاوند کے ازدواجی حقوق ادا کرے.اس پر یہ فرض بھی عائد ہوتا ہے
کہ وہ خاوند کی وفادار اور معروف طریق پر اس کی اطاعت گزار ہو.تیسرا فرض اس پر یہ عائد ہوتا ہے کہ وہ طلاق یا خاوند کی وفات کی صورت میں عدت گزارے.خاوند کے حقوق و فرائض
ر :- خاوند نکاح کے نتیجہ میں بیوی سے ازدواجی تعلقات یعنی مقاربت کا حقدار ہوتا ہے.اسی طرح گھریلو کام کاج اور بچوں کی پرورش کے سلسلہ میں بیوی سے مدد لینے کا حق بھی خاوند کو
حاصل ہوتا ہے.ب : خاوند پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ بیوی کا حق مقاربت اور نان و نفقہ ادا کرے
اور اس کی رہائش کا انتظام کرے.نفقہ کے بارہ میں خاوند کی ذمہ داری ملتی ہے بیوی کے صا-
جائیداد یا صاحب ثروت ہونے سے خاوند کی یہ ذمہ داری ساقط نہیں ہوتی ہے
ہے.ج : خاوند بیوی کو حق مہر ادا کرنے کا ذمہ دار ہے سیکھ
1.ایک سے زائد بیویوں کی صورت میں خاوند ان کے ساتھ مساوی سلوک کرنے کا پابند
تفصیل کے لئے دیکھیں دفعہ نمبر ۴۴
"
"
دفعہ نمبر ۹
Page 57
۵۴
دفعہ نمبر ۱۷
نکاح فاسد
ایسا نکاح جس میں صحت نکاح کی ابدی حرمت کی شرط کے علاوہ کوئی اور
شرط مفقود ہو مثلاً بوقت نکاح ولی کی اجازت نہ لی گئی ہو یا ایجاب و قبول کے
وقت گواہاں موجود نہ ہوں یا نکاح موقت ہو.تشریح
نکاح فاسد اور اس کے احکام کے بارہ میں یہ جاننا ضروری ہے کہ نکاح فاسد کا حکم کیسی
نکاح پر صرف ایسی صورت میں لگایا جاتا ہے جب کہ اس نکاح کے نتیجہ میں فریقین کے درمیان ازدواجی
تعلق قائم ہو جائے اگر ازدواجی تعلق قائم نہ ہوا ہوا اور نکاح کا فساد علم میں آجائے تونکاح واجب
الفسخ ہوگا اور فوری تفریق لازمی ہوگی اور فریقین کو کوئی حقوق حاصل نہیں ہوں گے، لیکن اگر فنسخ سے
پہلے ازدواجی تعلق قائم ہو جائے تو شہد فی المعقد کی بناء پر حد زنا ساقط ہوگی.اگر وجد فساد عامنی
ہے تو ضیح کے فیصلہ سے پہلے اس کے دُور ہونے پر پہلا نکاح ہی بحال رہے گا اور اعلان نکاح کے
بعد سے ہی فریقین کے جملہ حقوق اور ان کی تمام ذمہ داریاں قائم متصور ہوں گی لیکن اگر فساد بنیادی
ان تمام
شرائط میں پایا جائے تو ایسا نکاح ہر حال لازم انسخ ہو گا جیسے عدت کے دوران کیا ہوا نکاح واجب الفخ
ہے اور اس وجہ فساد کے دُور ہو جانے کے بعد اگر فریقین ازدواجی تعلق قائم کرنا چاہیں تو دوبارہ نکاح
پڑھنا ضروری ہوگا.
Page 58
۵۵
دفعہ نمبر ۱۸
اگر نکاح فاسد کے فسخ ہونے سے پہلے فریقین میں ازدواجی تعلق قائم ہوگیا ہو
تو حرمت مصاہرت واقع ہو گی اولاد ثابت النسب ہوگی اور مہر مشکل یا مهر مسمی
میں رقم
ی سے کم تر ر تم خاوند کے قتہ قابل ادا ہوگی اور بصورت تفریق عورت کے لئے
عدت گزارنا لازمی ہو گا.تشریح
نکاح فاسد کے نتیجہ میں اگر ازدواجی تعلقات قائم نہ ہوئے ہوں تو جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا
ہے علم ہونے پر نکاح فسخ کر دیا جائے گا اور فریقین میں تفریق کروا دی جائے گی.اس صورت میں اس
نکاح کے کوئی اثرات مرتب نہ ہوں گے.لیکن اگر ازدواجی تعلقات قائم ہوگئے ہوں تو مصاہرت لازم
آئے گی یعنی بیوی کی ماں، بیوی کی بیٹی ، سب حرام ہوں گی.اسی طرح یہ عورت اپنے اس خاوند کے والد
سے نکاح نہیں کر سکے گی اور نہ اس کے بیٹے سے.شریعت کے تمام احکام میں چونکہ سہولت مد نظر ہے اس لئے گو نکاح فاسد ہے لیکن اس کے
نتیجہ میں پیدا ہونے والی اولاد ثابت النسب ہوگی شریعت حتی الامکان بچے کو نا جائز یا حرام کے حکم سے
بچانا چاہتی ہے اس لئے جہاں کہیں تھوڑا سا سہارا بھی ملتا ہو خواہ شبہ فی الفعل ہو یا شبه في العقد
وہاں اس کے نتیجہ میں پیدا ہونے والی اولاد کو ولد الحرام کی تہمت سے بچانا مد نظر رکھا گیا ہے.نکاح فاسد کے نتیجہ میں حق مہر بھی ایسی صورت میں واجب الادا ہے جب تعلقات ازدواجی قائم
ہو چکے ہوں ورنہ نہیں البتہ مہر مثل اور مہر
سمتی میں سے جو کم تر ہو گا وہ واجب الادا ہو گا.اسی طرح
سے گو نکاح فاسد ہے لیکن اگر ازدواجی تعلقات قائم ہو گئے ہوں تو بصورت تفریق عورت پر عدت
لازم آئے گی تا کہ استقرار حمل کے بارہ میں تسلی کر لینے کا موقع مل سکے.
Page 59
AY
دفعہ نمبر ۱۹
نکاح باطل ایسا نکاح ہے جس کی کوئی شرعی بنیاد نہ ہو جیسے کسی دوسرے کی
منکوحہ سے نکاح یا محرمات ابدی سے نکاح.تشریح جو نکاح نصوص قطعیہ کے خلاف ہو وہ باطل ہے.فقہاء نے لفظ باطل اور لفظ فاسد کے
استعمال میں بعض جگہ غلطی کھائی ہے اور فاسد نکاح کے لئے باطل اور نکاح باطل کے لئے فاسد کے
الفاظ استعمال کئے ہیں.یہ غلطی اس وجہ سے لگی ہے کہ بعض اوقات ایک نکاح بظا ہر باطل ہوتا ہے
لیکن اس پر جو اثرات واحکام مرتب ہوتے ہیں وہ فاسد نکاح کے ہوتے ہیں مثلاً ایک شخص غلطی اور لا علمی
میں معدہ غیر سے نکاح کر لیتا ہے یا لا علمی میں محرمات ابدی میں سے کسی سے نکاح کر لیتا ہے.بظاہر تو یہ
نکاح باطل
کی تعریف میں آتا ہے لیکن اثرات اور نتائج کے لحاظ سے اس پر نکاح فاسد کے احکام مرتب ہوتے
ہیں.یہ امر سمجھ لینا چاہیئے کہ ان صورتوں میں جو نکاح فاسد کے بعض احکام مرتب ہوتے ہیں وہ نکاح کے احکام
نہیں بلکہ وٹی اور جماع کے احکام ہیں اور یہ احکام فقہاء نے صرف اس لئے مرتب کئے ہیں تاکہ اس جماع کے
نتیجہ میں پیدا ہونے والی اولاد کو ولد الحرام ہونے کے حکم سے بچایا جاسکے کیونکہ شعبہ فی المحل یا شبہ فی الفعل
کی وجہ سے یہ زنا نہیں ہے لیکن اس قسم کے نکاح کے بعد مرد اور عورت کے درمیان اگر تعلقات زوجیت قائم
نہیں ہوئے تو اس صورت میں سب کے نزدیک اس پر نکاح باطل کے احکام لاگو ہوں گے یعنی ہر دو میں
في الفور تفریق کرا دی جائے گی مرد کے لئے وطئی کرنا حرام ہوگا اور عورت کے لئے اس مرد کو مباشرت کا موقع
دینا حرام ہوگا.غرضیکہ ایک ہی فعل پر دو قسم کے احکام نافذ ہونے کی وجہ سے فقہاء نے فاسد" اور "باطل" کے الفاظ
استعمال کرنے میں تسامح سے کام لیا ہے تاہم بنیادی اصول یہی ہے کہ جو نکاح نصوص قطعیہ کے خلاف ہو وہ
باطل ہے اور جس میں نکاح
صحیح کی شرائط کے لحاظ سے کوئی ایسا ستم ہو جس کا لبسہولت ازالہ ہو سکتا ہو وہ
نکاح فاسد ہے.
Page 60
دفعہ نمبر ۲۰
تشریح
نکاح باطل کا لعدم کے حکم میں ہے اور اس کے نتیجہ میں فریقین کو کوئی حقوق
حاصل نہیں ہوتے.نکاح باطل چونکہ فعل حرام ہے اس لئے خواہ خلوت صحیحہ میتر بھی آجائے اس سے (سوائے
بعض استثنائی صورتوں کے) کوئی حقوق پیدا نہیں ہوتے بلکہ فریقین حملہ حقوق سے محروم ہوتے ہیں.عورت کے لئے حق مہر اور عدت نہیں.فریقین ایک دوسرے کے وارث نہیں.اسی طرح اولاد ثابت النسب
نہیں ہوگی.تفصیل کے لئے دیکھیں دفعہ نمبر 19 کی تشریح.
Page 61
۵۸
دفعہ نمبر ۲
تعدد ازدواج
مرد شرعی ضرورت اور عدل و مساوات کی شرائط کی پابندی کے ساتھ ایک
سے زائد نکاح کر سکتا ہے لیکن بیک وقت چار سے زائد بیویاں نہیں رکھ
تشریح
سکتا ہے
قانون فطرت اور معاشرہ کے بعض مخصوص حالات کے پیش نظر تعدد ازدواج ایک اہم
معاشرتی ضرورت ہے.اسلام جو کہ دین فطرت ہے اس نے اس ضرورت کو نظر انداز نہیں کیا اور بعض شرائط کی پابندی
کے ساتھ تعدد ازدواج کی اجازت دی ہے.اگر کسی بھی صورت میں تعدد ازدواج کی اجازت نہ ہو اور
اسے ایک دینی حکم قرار دیا جائے تو معاشرے کو سخت مشکلات اور نا گفتہ بہ قباحتوں کا سامنا کرنا پڑے گا.اس بناء پر قرآن کریم نے بعض مصالح کے پیش نظر مردوں کو ایک سے زائد شادیوں کی اجازت دی
ہے ایسے مصالح کی بعض صورتیں یہ ہو سکتی ہیں.: قومی حالات کا تقاضا مثلاً کسی جنگ کے نتیجہ میں مردوں کی تعداد بہت کم ہو جائے اور
عورتوں کی تعداد نسبتا بہت زیادہ ہو جائے.ب.دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ عورت بیمار ہو اور ازدواجی ذمہ داریوں کی ادائیگی
کے قابل نہ ہو ایسی صورت میں اگر مرد دوسری شادی کرنے کی اجازت چاہے تو عدل و مساوات کی شرط
کے ساتھ اسے دوسری شادی کی اجازت نہ دینا انسانی فطرت پر ظلم کے مترادف اور جذبہ تراحم کے
خلاف اقدام ہوگا.له سورة النساء آیت نمبرم
Page 62
۵۹
دوسری شادی کی اجازت نہ دینے کی وجہ سے دوہی صورتیں پیدا ہو سکتی ہیں ایک یہ کہ بیوی کی
بیماری کی وجہ سے خاوند بھی عملاً تجرد کی زندگی پر مجبور ہو جائے جو بذات خود قانون فطرت سے بغاوت ہے
دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ مرد خود کو دوسری شادی کے لئے آزاد کرنے کی خاطر بیمار بیوی کو طلاق دیدے
اور خود دوسری شادی کرلے حالانکہ پہلی بیمار بیوی علیحد گی نہیں چاہتی.پس ان حالات میں معقول صورت وہی ہے جو اسلام نے پیش کی ہے اور عدل و مساوات کی شر
کے ساتھ دوسری شادی کرنے کی اجازت دی ہے تاکہ بیمار بیوی اپنے سہارے سے بھی محروم نہ ہو اور
اس کا شوہر محض بیوی کی بیماری کی وجہ سے فطرت سے بغاوت پر بھی مجبور نہ ہو.یہی صورت عورت کے بانجھ ہونے کی وجہ سے پیدا ہو سکتی ہے اس کے علاوہ مرد طبعی طور پر بھی
بعض اوقات ایک سے زائد شادیوں کی ضرورت محسوس کر سکتا ہے.اس صورت میں مغربی معاشرہ اپنے
افراد کو دوسری شادی کی اجازت تو نہیں دیتا مگر شادی کے بغیر جنسی تعلق کو برداشت کر لیتا ہے لیکن
اسلام شادی کے بغیر جنسی تعلق کو روا نہیں رکھتا بلکہ اس کے نزدیک معاشرے کی صحت مند تشکیل اور
ذمہ داری کے احساس کو اجاگر کرنے کے لئے غیر شادی شدہ ملاپ کی بجائے تعدد ازدواج کی اجازت
دینا اقرب الی الصواب ہے.اسلام نے ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کی اجازت عدل و مساوات کی شرط کے ساتھ مشروط کی
ہے جیسا کہ فرمایا :-
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً له
یعنی اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ تم عدل نہ کر سکو گے تو ایک ہی عورت سے نکاح کرو.لہذا اگر کوئی شخص ایک سے زائد شادیاں کرنے میں عدل کی شرط کو ملحوظ نہ رکھ سکے یا پہلی بیوی
سے ظالمانہ سلوک روا رکھے اور دوسری شادی میں اس کی رضامندی کو ملحوظ نہ رکھے نہ اسے اطلاع دے
اور نہ اس کے حقوق کی ادائیگی کرے اور نہ سب کے ساتھ عدل قائم رکھنے کا یقین دلائے تو حالات کے
مطابق مناسب قانون کے ذریعہ ایسے شخص کو ایک سے زائد شادیاں کرنے سے روکا جاسکتا ہے یا پہلی
ں
بیوی کو اس کے جملہ حقوق کے ساتھ حق علیحدگی" دیا جا سکتا ہے.ل سورة النساء آیت م
Page 63
4.دفعہ نمبر ۲۲
ولادت اور نسب
کسی بچے کا نسب ولادت سے یا مرد کے اقرار سے ثابت ہوتا ہے.دفعہ نمبر ۲۳
ولادت سے نسب ثابت ہونے کے لئے ضروری ہے کہ
و بچه نکاح صحیح یا نکاح فاسد کے بعد پیدا ہو.ب - مرد اور عورت مباشرت کے قابل ہوں.ج : بچہ کی ولادت نکاح کے بعد طبیعی مدت عمل میں واقع ہوئی ہو.دفعہ نمبر ۲۴
مجمول النسب بچے کا نسب مرد کے اقرار سے متعین ہو سکتا ہے بشرطیکہ بچہ عمر
کے لحاظ سے اقرار کرنے والے کی بیٹی یا بیٹا ہوسکتا ہو اور حالات معلومہ کے
مطابق ایسا ہونا عقلاً محال نہ ہو.
Page 64
دفعہ نمبر ۲۵
۶۱
شرائط مندرجہ دفعہ نمبر ۲۴ کے تحت اقرار نسب کے بعد بیمہ کا نسب متعین
ہو جائے گا اور بعد ازاں اقرار کرنے والا اس سے منکر نہیں ہو سکے گا.تشریح دفعات نمبر ۲۳، نمبر ۲۴، نمبر ۲۵
:- اسلام میں بچے کے نسب کو حتی الامکان صحیح قرار دینے کی کوشش کی گئی ہے.اگر ولادت
ایسے حالات میں ہوئی ہے جن کا ذکر دفعہ نمبر ۲۳ میں ہے تو بچے کا نسب ولادت سے بلا دعوی ثابت
ہوگا اور اس میں کلام کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی.دعوای کے بغیر محض ولادت سے نسب ثابت کرنے کے لئے پہلی شرط یہ ہے کہ بچہ نکاح کے بعد
پیدا ہوا ہو نکاح سے پہلے بچے کی پیدائش سے خود بخود نسب ثابت نہیں ہوتا جیسا کہ دفعہ نمبر ۲۳
میں مذکور ہے.پس ولادت سے نسب ثابت کرنے کے لئے ضروری ہے کہ بچہ نکاح صحیح یا نکارج خامد
کے بعد پیدا ہوا ہو.دفعہ مذکور میں زور نکاح کے صحیح یا فاسد اور اس کے معتبر ہونے پر نہیں
بلکہ نکاح تنقیح یا نکاح فاسد کے بعد پیدائش پر ہے.البتہ نکاح باطل کے بعد عام حالات میں پیدائشی
سے نسب ثابت نہیں ہوتا.دوسری شرط یہ ہے کہ مرد اور عورت مباشرت کے قابل ہوں.اگر خاوند یقینی طور پر نا بالغ
ماہ
ہو تو محض ولادت کی بناء پر بچے کا نسب ثابت نہیں ہوگا.تیسری شرط یہ ہے کہ بچہ نکاح کے بعد کم ازکم چھ ماہ کا عرصہ پورا ہونے یا اس کے بعد پیدا
ہوا ہو.اگر بچہ چھ ماہ سے پہلے پیدا ہوا ہو تو محض ولادت سے نسب ثابت نہیں ہوگا.اس سلسلہ میں اُصول یہ ہے کہ نکاح کے بعد بچے کی ولادت طبعی مدت حمل میں ہوئی ہو.طبعی مدت حمل سے مراد کم سے کم مدت حمل بھی ہو سکتی ہے اور زیادہ سے زیادہ مدت حمل بھی.جمل کی کم از کم مدت نکاح کے بعد چھ ماہ ہے اور یہ مدت حمل آیاتِ قرآنی سے مستنبط ہے
جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا :-
ے وضاحت کے لئے دیکھئے دفعہ نمبر 19 نکاح باطل اور اس کی تشریح.
Page 65
۶۲
وحَمْلُهُ وَفِضْلُهُ ثَلْتُونَ شَهْرًا
یعنی اس کے جنین کی صورت میں اُٹھانے اور اس کے دُودھ چھڑانے پر میں ہے
لگے تھے.ایک اور جگہ فرمایا :
وَفِضْلَهُ فِي عَامَيْنِ
یعنی اس کا دودھ چھڑانا دو سال میں ہوا.گویا باری تعالیٰ نے حمل اور فصال کی مجموعی مدت تین ماہ قرار دی ہے اور فصال یعنی دودھ
چھڑانے کی مدت دو سال.اِس طرح حمل کی کم از کم مدت چھ ماہ ٹھہرتی ہے لہذا اگر بچہ نکاح کے چھ
ماہ بعد پیدا ہوا ہو تو وہ بدوں دعوی ثابت النسب ہو گا.اس سے کم مدت میں پیدا ہونے والا
بچه محض ولادت کی بناء پر ثابت النسب نہیں ہوگا.زیادہ سے زیادہ مدت حمل عمومی طور پر اگرچه ۲۸۰ یوم بنتی ہے مگر امام ابوحنیفہ نے استثنائی
صورتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اور بچے کے نسب کو حتی الامکان صحیح ٹھہرانے کے لئے زیادہ سے زیادہ
مدت حمل دو سال قرار دی ہے اس لحاظ سے ان کے نزدیک خاوند کی وفات کے بعد اگر کوئی بیوہ
دو سال کی مدت کے اندر اندر بچہ جنے اور دعوی کرے کہ یہ اس کے فوت شدہ خاوند کا بچہ ہے تو
قانونا اسے درست اور ثابت النسب سمجھا جائے گا یعنی وہ بچہ اس کے فوت شدہ خاوند کا ہوگا لیکن
اس دعوی کی بناء پہ نہ کہ محض ولادت کی بناء پر.جماعت احمدیہ کے نز دیک طبعی مدت حمل کا فیصلہ قانون اور طبعی شواہد کے مطابق ہونا چاہیئے
کیونکہ خدا کا قول اس کے فعل کے خلاف نہیں ہو سکتا اس لئے صحت نسب کے لئے قوانین طبیعی کو
نظر اندازہ نہیں کیا جا سکتا.پس متنازعہ فیہ صورت میں ماہر اطباء کی رائے کو اہمیت دی جائے گی ہیں
ب :- اقرار کی بناء پر ثبوت نسب :-
اگر ولادت ایسے حالات میں ہوئی ہو کہ اس سے نسب متعین نہ ہوتا ہو یا اس میں کوئی شبہ
له سورة لقمان آیت ۱۵
له سورة الاحقاف آیت ۱۶
سے مدت حمل کی اکثر طبیبوں کے نز دیک ڈھائی برس بلکہ بعض کے نز دیک انتہائی مدت حمل کی تین برس
تک بھی ہے.مجموعہ اشتہارات حضرت مسیح موعود جلد اوّل صفحہ ۱۲۸ شائع کردہ الشرکة )
Page 66
۶۳
ہو تو اسلام نے قطع نظر ولادت کے مرد کے محض اقرار سے نسب کو درست تسلیم کیا ہے لیکن اس طرح
محض اقرار کے ذریعہ نسب درست ٹھہرانے کے لئے ضروری ہے کہ اقرار کرنے والے اور بچے کی عمر
میں اتنا تفاوت ضرور ہو کہ مقر کا باپ ہونا عقلاً محال نہ ہو.بعض فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ اقرار کرنے والا کم از کم ساڑھے بارہ سال اس شخص سے بڑا
ہو جس کے باپ ہونے کا وہ اقرار کرتا ہے.فقہ احمدیہ میں اس کے لئے ماہ و سال کی تعیین ضروری
نہیں البتہ حالات معلومہ کے مطابق مقر کا باپ ہونا عقلاً محال نہیں ہونا چاہیئے.اسی طرح اقرار
ایسا ہونا چاہیے کہ اس کی وجہ سے ولادت کو صحیح قرار دینا دیگر پہلوؤں کے لحاظ سے ایک حد تک
ممکن ہو.چنانچہ مندرجہ ذیل صورتیں ایسی ہیں کہ ان میں اقرار کے با وجو د نسب ثابت نہیں ہوگا.ا جبکہ بچہ کا ولد الزنا ہونا ثابت ہو چکا ہو.ب.جن کا دعوی ہو وہ دونوں میاں بیوی رہے ہوں اور ان کے درمیان لعان ہو چکا ہو.ج - اقرار کرنے والے اور مقرلہ کی عمروں میں اتنا تفاوت ہو کہ ان کا آپس میں باپ بیٹا ہونا ممکن نہ
ہو.د - بچے کا نسب معروف ہوں.بچے کی ماں کیسی دوسرے شخص کے نکاح میں ہونے کی وجہ سے اقرار کرنے والے کی کیسی جہت
سے زوجہ نہ بن سکتی ہو.و.بچہ اس اقرار کی تردید کرتا ہو.ز - اقرار کرنے والا اس سے قبل کسی شکل میں انکار کر چکا ہو اور اس انکار کی وجہ سے اس کے
خلاف فیصلہ ہو چکا ہو.مندرجہ بالا صورتوں کے علاوہ باقی صورتوں میں مقر کا اقرار نسب درست سمجھا جائے گا اور
اقرار کرنے کے بعد وہ اس نسب سے انکار نہیں کر سکے گا.
Page 67
۶۴
دفعہ نمبر ۲۶
اگر نکاح کے بعد اقل مدت حمل سے پہلے بچہ پیدا ہو اور خاوند بچے کا
باپ ہونے سے انکار کرے تو اس کا نسب ثابت نہیں ہوگا.تشریح : دفعہ نمبر ۶ ۲ تا دفعہ نمبر ۳۱ در حقیقت نسب سے متعلق بعض منفی صورتیں ہیں.چونکہ منفی
صورتوں میں بچے اور اس کی ماں کے حقوق پر اثر پڑتا ہے اس لئے ان کو الگ بالتفریح بیان کر دیا
گیا ہے.اقل مدت حمل سے پہلے بچے کی پیدائش کی صورت میں اگر خاوند بچے کا باپ ہونے کا اقرار
کرے تو اس اقرار کی بنیا د پر اس کا نسب ثابت ہوگا کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:
الوَلَدُ للفِرَاشِ وَالْعَاهِرِ الْحَجَرُ له
یعنی شریعت نے فراش اور نکاح کو اثبات نسب کا مدار قرار دیا ہے.فراش سے مراد مرد
اور عورت کا وہ تعلق ازدواج ہے جس کی شریعت نے اجازت دی ہے یعنی یہ تعلق نکاح کی بنیاد
پر قائم ہوا ہوتا ہم اس صورت میں اگر خاوند ثبوت نسب سے انکار کرے تو اسے لعان کرنے پر مجبور
نہیں کیا جائے گا کیونکہ بظا ہر حالات اس کا یہ انکار درست معلوم ہوتا ہے.درحقیقت عورت کے لبطن
سے بچے کی پیدائش محسوس اور مشہور ہوتی ہے اِس لئے اگر وہ بچے کی ولادت سے انکار بھی کرے تو
اس کا یہ انکار درست تسلیم نہیں کیا جائے گا کیونکہ اس کا انکار مشاہدہ کے خلاف ہے لیکن باپ کی
ابوت محسوس اور مشہور نہیں ہوتی اس لئے اس کے انکار کی صورت میں طبعی حالات کو دیکھا جائے گا.اگر طبعی حالات اس کے انکار کی تردید نہیں کرتے تو اس کے انکار کو درست تسلیم کر لیا جائے گا اور
ایسی صورت میں اسے لعان کرنے یا کوئی اور قانونی ثبوت پیش کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا.له بخاری کتاب الفرائض باب من ادعى اخا او ابن اخر منت - ابوداؤد ما
1
Page 68
۶۵
دفعہ نمبر ۲۷
اگر خاوند قاضی کے سامنے اپنی بیوی پیر الزام لگائے کہ اس نے ناجائز بیتہ
جنا ہے اور بیوی اس الزام کو درست تسلیم کرے تو مولود کا نسب ثابت
نہیں ہوگا.تشریح :-
چونکہ انکار نسب یا انتفاء نسب بہت سے حقوق و فرائض پر اثر انداز ہوتا ہے مثلاً وہ
دونوں ایک دوسرے کی وراثت سے محروم ہو جاتے ہیں خاوند پر اس بچے کے نان و نفقہ کی ذمہ داریاں
ختم ہو جاتی ہیں اس لئے اس قسم کا ادعا یا الزام لگانا قاضی کے روبر و ضروری ہے تاکہ یہ امریکارڈ
میں آجائے اور خاوند دیگر قانونی الجھنوں سے نجات حاصل کر لے اس الزام اور دعوی کو صرف
اس صورت میں درست سمجھا جائے گا جبکہ بیوی بھی اس الزام کو درست تسلیم کرے ورنہ خاوند کو لعان
پر مجبور کیا جائے گا اور لعان سے انکار کی صورت میں اسے زنا کی تہمت (قذف) کا مجرم قرار دیا
جائے گا اور نسب بھی ثابت ہوگا بشرطیکہ دوسری شرائط موجود ہوں.دفعہ نمبر ۲۸
اگر خاوند اور بیوی قاضی کے سامنے لعان کریں اور ساتھ ہی خاوند انکار
نسب کرے تو مولود کا نسب ثابت نہ ہوگا.تشریح :- جمهور فقہاء کے نزدیک لعان کی تعریف یہ ہے کہ جب خاوند قاضی کے سامنے جا کر اپنی
بیوی پر زنا کا الزام لگائے تو قاضی کے سامنے خاوند چار مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر شہادت دے کہ اس نے
له سوائے اس کے کہ قاضی سیاستا خاوند کو بچہ کے نان و نفقہ کا ذمہ دار قرار دے.
Page 69
۶۶
زنا کرتے دیکھا ہے اور اس الزام ہیں وہ سچا ہے اور پانچویں شہادت یہ دے کہ اگر وہ اپنے دعوی میں
جھوٹا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو.اس کے بعد اس
کی بیوی اگر الزام کی صحت سے انکار کرے تو وہ اللہ کی قسم کھا کر چار مرتبہ یہ
کہے کہ اس کا خاوند یہ الزام لگانے میں جھوٹا ہے اور پانچویں قسم اس طرح کھائے کہ اگر اس کا خاوند
سچا ہے تو خدا کا غضب اس پر (یعنی مجھ پر) نازل ہو.لعان کا ثبوت اللہ تعالٰی کے اس ارشاد سے ہوتا ہے :-
وَالَّذِينَ يَرْمُونَ ازْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةٌ
احدِهِمْ اَرْبَعُ شَهَدَتِ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصُّدِقِيْنَ ، وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ
اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَذِبِينَ ، وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ ارْبَعَ
شَهَدَتِ بِاللهِ اِنَّهُ لَمِنَ الْكَذِبِينَ : وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ
كَانَ مِنَ الصَّدِقِينَ.یعنی جو لوگ اپنی بیویوں پر زنا کا الزام لگاتے ہیں اور ان کے پاس سوائے اپنے وجود
کے اور کوئی گواہ نہ ہو تو ان میں سے ہر شخص کو ایسی گواہی دینی چاہئے جو اللہ کی قسم
کھا کر چار گواہیوں پرشتمل ہوا ور ہر گواہی میں وہ یہ کہے کہ وہ راستبازوں میں سے
ہے اور پانچویں گواہی میں کہے کہ اس پر خدا کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹوں میں سے ہو.اور وہ بیوی جس پر اس کا خاوند الزام لگائے اپنے نفس پر سے چار ایسی گواہیوں کے
ذریعے سے جو قسم کھا کر دی گئی ہوں عذاب دُور کرے.یہ کہتے ہوئے کہ وہ خاوند جھوٹا
ہے.اور پانچویں قسم اس طرح کھائے کہ اللہ کا غضب اس عورت پر نازل ہو اگر وہ
الزام لگانے والا خاوند تیچا ہے.لعان کا حکم در حقیقت خاوند اور بیوی ہر دو کے لئے شریعت کی طرف سے بہت بڑا احسان ہے
بلکہ اس کے ذریعہ سے خاوند حد قذن سے بچ جاتا ہے اور بیوی حد زنا اسے بیٹے
لعان کے بعد فریقین کے درمیان تفریق لازم ہے کیونکہ اس تفریق کی وجہ سے فریقین ایک دوسرے
سورة النور آیت ۷ تا ۱۰
سے رائج الوقت قانون کے تحت اس وقت یہ حدیں نافذ العمل نہیں.
Page 70
کے خلاف بغض و عناد کی آگ سے محفوظ ہو جاتے ہیں اور خاوند بچے کے نان و نفقہ کی ذمہ داریوں
سے آزاد ہو جاتا ہے یہ
اگر خاوند کی طرف سے صرف زنا کا الزام ہو تو لعان کے بعد دونوں کے درمیان تفریق واجب
ہے لیکن اگر زنا کے الزام کے علاوہ بچے کے نسب کی نفی کا دعوامی بھی شامل ہو تو اس صورت میں لعان
کے بعد خاوند سے مولود کا نسب ثابت نہ ہو گا جیسا کہ ابن عباس کی روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے بلال ابن امیہ اور اس کی بیوی کے درمیان لعان کے بعد بچے کی نسب صرف اس کی ماں کے
ساتھ منسلک کردی تھی.روایت کے الفاظ یہ ہیں :-
لا عن بَيْنَ الرَّجُلِ وَامرَأَتِهِ فَانتَفى مِنْ وَلَدِهَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَالْحَقَ
الْوَلَد بِالْمَرأَة - له
یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرد اور عورت کے درمیان لعان کروایا اور مرد نے
اس لڑکے کی نفی کا بھی دعوای کیا.اس بناء پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں میں تفریق کرا
دی اور بچہ عورت کے ساتھ ملحق کر دیا.لیکن یہ نفئی ولادت صرف اس صورت میں مؤثر ہو گی جب کہ نفی کرنے والا اس سے پہلے کسی وقت
صراحتاً یا کفایہ اقرار نسب نہ کر چکا ہو.اقرار نسب کے بعد انکار درحقیقت ایک مسلمہ حقیقت سے
انکار ہے جو شرعاً اور قانوناً جائز نہیں ہے.کنایہ اقرار نسب سے مراد یہ ہے کہ مثلاً وہ ایک وقت تک بچے کے نان و نفقہ کی ذمہ داری خاموشی
سے برداشت کرتا رہا ہو یا بیوی اور دیگر عزیز و اقارب کی طرف سے اس بچے کا نسب اپنی طرف منسوب
ہوتے ہوئے سنتا رہا ہو اور کسی مرحلہ پر اس نے انکار یا انحراف نہ کیا ہو تو ان سب صورتوں میں
اس کی طرف سے نفی ولادت مؤثر نہ ہوگی اور نہ وہ بچے کے نان و نفقہ کی ذمہ داریوں سے بری ہو گا.لے سوائے اس کے کہ دینی مصلحت کا تقاضا ہو کہ لعان کے باوجود خاوند بیچتے کے نان و نفقہ کا ذمہ دار
ہے.له بخارى كتاب الطلاق باب يلحق الولد بالملاعنة جلد ۲ صفحه ا
A.I
Page 71
Чл
دفعہ نمبر ۲۹
اگر کوئی شخص اس بناء پر کسی بچے کا باپ ہونے سے انکار کرے کہ بیوی
سے عدم مقاربت کی وجہ سے یا دیگر وجوہات کی بناء پر عقلاً وطبعا وہ بحیہ اس کا
نہیں ہو سکتا تو باپ کا یہ دعوی ثابت ہونے پر بیچنے کے نسب کی نفی ہو
جائے گی.تشریح:- زیادہ سے زیادہ مدت حمل جیسا کہ دفعہ نمبر ۲۳ تشریح الف کے تحت بیان کیا جا چکا ہے
قانون شرعی اور طبعی شواہد یعنی ماہر اطباء کی رائے کے مطابق قرار پائے گی.اگر ان شواہد کے مطابق
خاوند اپنی بیوی سے اتنا عرصہ الگ رہا ہو کہ بچہ کا اس کے نسب سے ہونا بظا ہر حالات ممکن نہ ہو تو
اس صورت میں خاوند کے لئے لعان لازم نہیں ہو گا اور نسب
کی نفی کے لئے صرف الگ رہنے کا
ثبوت پیش کرنا کافی ہوگا.دفعہ نمبر ۲
پرورش کی بناء پر کوئی شخص تقسیط کا ولی نہیں بن سکتا اور نہ ہی لقیط اور
پرورش کنندہ ایک دوسرے کے وارث ہوتے ہیں.تشریح :- لقیط اس لاوارث بچے کو کہا جاتا ہے جوکسی عام جگہ پڑا ہوا کسی کو بل جائے اور وہ اسے
ہے.اُٹھا لے اور اس کی پرورش کی ذمہ داری قبول کرے.ایسا لاوارث بچہ جس کی پرورش کی ذمہ داری کوئی شخص
قبول نہ کرے اس کی پرورش کی ذمہ داری حکومت اور بیت المال پر ہو گی.
Page 72
۶۹
حضرت عمر کے زمانہ میں اس
قسم کا ایک بچہ پڑا ہوا ملا تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اس بچے کی پرورش
کا خرچ بیت المال سے ادا ہو گا.اسی طرح حضرت علی رضہ نے بھی ایسے بچے کے لئے یہی فیصلہ فرمایا ہے
ہدایتہ میں ہے کہ اگر ایک شخص کسی بچے کو پڑا پائے اور اس کی پرورش قبول کرے تو کسی دوسرے
شخص کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اس کی مرضی کے بغیر اس سے وہ بچہ نے لے لیکن اگر دوسرا شخص اس
بچے کے نسب کا دعوی کرے اور کوئی اور شخص اس کے نسب کا مدعی نہ ہو اور حالات کے لحاظ سے یہ دعوای
درست لگتا ہو اور قرائن اس کی تائید کرتے ہوں تو اس کے دعوام کو درست تسلیم کیا جائے گا.صاحب ہدایہ کے نزدیک یہ دعوای راستحسانا صحیح ہوگا کیونکہ اس دعوای کی بناء پر
و اچھے کو شفقت پدری حاصل ہو گی.ب.اسے نسب کا شرف حاصل ہو جائے گا جس سے وہ پہلے محروم تھا.ج.اور وہ ولد الزنا کی تہمت سے محفوظ ہو جائے گا.یہ سب امور بچے کے فائدہ کے لئے ہیں اس لئے اس دعوی کو درست تسلیم کیا جائے گا.و عوامی نسب کے بغیر محض پرورش کی بناء پر پرورش کنندہ اور لقیط ایک دوسرے کے وارث نہ ہونگے
بعض اوقات بے اولاد لوگ جو بچے ہسپتالوں یا رفاہی اداروں سے حاصل کر لیتے ہیں یا قدرتی آفات
وغیرہ کے نتیجہ میں جو بچے اپنے والدین سے بچھڑ جاتے ہیں اور کوئی ان کو لے کر پال لیتا ہے یہ سب لقیط کے
حکم میں ہوں گے.له مؤطا امام مالك كتاب الأقضيه باب القضاء فى المنبوذ ه و نصب المرايه جلد۳ ۴۶۵
ه هدايه كتاب اللقيط جلد ۲ ص
0<4
Page 73
دفعہ نمبر ۳۱
متبنی اور نبی بنانے والا قانونا اور شترنا ایک دوسرے کے وارث نہیں
ہوتے.تشریح:-
اسلام سے
قبل متدی بنانے کا رواج عام تھا اور اسے حقیقی بیٹے کی طرح جائیداد کا وارث
قرار دیا جاتا تھا لیکن اسلامی احکامِ وراثت کے نزول کے بعد ہر
قسم کے منہ بولے بیٹے یا دینی بھائی وراثت
کے حقدار نہ رہے.ہجرت کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات یعنی
بھائی چارہ کا تعلق قائم فرمایا تھا اور شروع شروع میں وہ وراثت میں بھی ایک دوسرے کے حقدار بن جاتے
تھے لیکن احکام وراثت کے نزول کے بعد سے کوئی منہ بولا بھائی یا کوئی منہ بولا بیٹا شرعی وارثوں کی
طرح وارث نہ رہا.اسلام سے قبل منہ بولے بیٹے کے ساتھ مہری رشتے بھی اسی طرح حرام سمجھے جاتے تھے جیسے حقیقی
بیٹے کے ساتھ.مثلاً بیٹا بنانے والا متبشی کی بیوی سے طلاق یا بیوگی کی صورت میں ) نکاح نہیں کر سکتا
تھا لیکن اسلام نے ایسے رواج
کو بھی منسوخ فرما دیا.چنانچہ الہ تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے :-
فلما قضى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَجُنُكَهَا لِكَيْ لَا يَكُوْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَج
في ازْوَاجِ اَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا، وَكَانَ اَهْرُ اللهِ مَفْعُولاهُ
یعنی جب زید نے اس عورت کے بارہ میں اپنی خواہش پوری کر لی اور اسے طلاق
دے دی تو ہم نے اس عورت کا تجھ سے بیاہ کر دیا تا کہ مومنوں کے دلوں میں اپنے
لے پالکوں کی بیویوں سے نکاح کرنے کے متعلق ان کو طلاق مل جانے کی صورت میں کوئی
خلش نہ رہے اور خدا کا فیصلہ ہر حال پورا ہو کر رہنا ہے.سے سورۃ الاحزاب آیت ۳۸
Page 74
1
باب الطلاق
بعض مذاہب میں نکاح لازمی طور پر عمر بھر کا بندھن ہوتا ہے اور کسی حالت میں بھی اسے
ختم نہیں کیا جا سکتا خواہ اس کا قائم رہنا فریقین کے لئے کتنی بھی شدید ذہنی اور جسمانی اذیت کا باعث
ہو لیکن اسلام ایسی سختی کا روادار نہیں جو تقاضہ فطرت کے منافی ہو.اسلام میں نکاح کو اس کی بعض
معاشرتی خصوصیات کی وجہ سے اگرچہ شرعی اور دینی تقدیس حاصل ہے لیکن اصلا چونکہ یہ ایک عمرانی
معاہدہ ہے اور فریقین کی یکساں رضامندی سے عمل میں آتا ہے نیز فقہائے اسلام نے عبادات اور
معاملات دونوں سے اس کا تعلق مانا ہے اس لئے اگر فریقین اس معاہدہ کو نبھانے کے قابل نہ رہیں
یا آپس میں نباہ نہ کر سکیں اور وہ اس معاہدہ کو ختم کرنے پر مجبور ہو جائیں تو باوجود اس کے دینی تقدیس
کے شریعت نے اس معاہدہ نکاح کوختم کرنے کی اجازت دی ہے کیونکہ اسلام نے انسانی فطرت کے
تقاضوں کو نظر انداز نہیں کیا اور حتی الوسع انسان کو ایسے حالات سے بچانے کی کوشش کی ہے جو اس
کے لئے ذہنی یا جسمانی اذیت کا باعث بنیں.دوسری طرف چونکہ اس معاہدہ کو دینی تقدس بھی حاصل ہے اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے اس معاہدہ کو ختم کرنے کو " ابغض العلال" کہا ہے اور اس میں جلد بازی سے منع کیا گیا ہے اور
کوشش کی گئی ہے کہ نکاح حتی الامکان برقرار رہے اور صرف اسی صورت میں یہ تعلق ختم ہو جب حقیقتاً
اس کے بغیر کوئی چارہ نظر نہ آئے.قرآن کریم اور احادیث کی روشنی میں میاں بیوی کی علیحدگی سے قبل اصلاح کی کوشش کی
غرض سے مندرجہ ذیل تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت ہے.1 نشوز اور اس کی اصلاحی تدابیر
نشور علیحدگی کا پیش خیمہ ہے.اس بارہ میں اصلاحی تدابیر کی طرف رہنمائی کرتے ہوئے اللہ
تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے :-
Page 75
۷۲
والتي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُرُهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ
فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ل
یعنی جن کی نافرمانی کا تمہیں خوف ہو تم انہیں نصیحت کرو اور انہیں خوابگا ہوں
میں اکیلا چھوڑ دو اور انہیں مارو پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کرنے لگیں تو ان کے
خلاف کوئی بہانہ تلاش نہ کرو.اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ نشوز کے تین درجے ہیں.چنانچہ امام راغب فرماتے ہیں :-
نُشُوزُ الْمَرْأَةِ بَعْضُهَا زَوْجَهَا وَرَفعُ نَفْسِهَا عَنْ طَاعَتِهِ وَعَيْنِهَا عَنْهُ
إلى غيره - له
یعنی عورت کا نشوز یہ ہے کہ وہ اپنے خاوند سے بغض رکھے اور اپنے آپ کو اس کی
اطاعت سے بالا سمجھے اور اپنی آنکھیں دوسرے مرد کی طرف اُٹھائے.نشوز کے ان مختلف درجات کے لحاظ سے آیت کریمہ میں یہ ہدایت ہے کہ
3 نشوز کی پہلی صورت میں عورت کو حکمت کے ساتھ سمجھایا جائے.ب.نشوز کی دوسری صورت میں ناراضگی کے طور پر اس سے کچھ مدت کے لئے ازدواجی تعلقات
منقطع کر لئے جائیں.ج.اگر ان ذرائع سے اصلاح نہ ہوا اور نشوز کی تیسری صورت کا سامنا ہو تو مرد کو اجازت ہے
کہ وہ بیوی کی مناسب جسمانی تادیب کرے.اصلاح کی اِن مذکورہ بالا تدابیر کے ناکام ہونے کی صورت میں مرد اور عورت دونوں کے
خاندانوں میں سے ایک ایک صاحب فہم و عدل نمائندہ مقرر کیا جائے یہ دونوں حالات کا جائزہ لینے
کے بعد وجۂ فساد دور کرنے کی کوشش کریں چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے :-
وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا
سورة النساء آیت ۳۵
ه المفردات للراغب زیر لفظ نشوز
Page 76
اِنْ تُرِيْدَا إِصْلَاحًا تُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا
یعنی اگر تمہیں ان دونوں میاں بیوی کے آپس کے تعلقات میں تفرقہ کا خوف ہو
تو ایک نمائندہ اس مرد کے رشتہ داروں سے اور ایک نمائندہ اس عورت کے
رشتہ داروں سے مقرر کہ وہ پھر اگر وہ دونوں پہنچ صلح کرانا چاہیں تو اللہ تعالیٰ ان
دونوں میاں بیوی کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا.اللہ یقینا بہت جاننے والا
اور خبردار ہے.پس اگر اس ذریعہ کو استعمال کرنے کے باوجود مصالحت نہ ہو سکے تو ابغض الحلال"
ہونے کے باوجود با مرمجبوری اسلام نے میاں بیوی کو بذریعہ طلاق یا ضلع علیحدگی اختیار کرنے کی
اجازت دی ہے.دفعہ نمبر ۳۲
تعلق نکاح جب مرد کی طرف سے ختم کیا جائے تو اسے طلاق اور جب عورت
کی طرف سے ختم کرنے کا مطالبہ ہو تو اسے خلع کہتے ہیں.تشریح:-
طلاق کے لفظی معنی " ازالہ الفقید" کے ہیں یعنی قید سے رہائی اور آزادی دینا اور اصطلاحی
معنی یہ ہیں کہ مرد کی طرف سے تعلق نکاح کو ختم کیا جائے اور وہ زبانی یا تحریر ی طور پر یہ کہہ کہ کہ کیس
تجھے طلاق دیتا ہوں عورت کو اُس پابندی سے آزاد کر دے جو معاہدہ نکاح کے ذریعہ اس پر عائد
ہوئی تھی.طلاق دیتے وقت خاوند کے لئے یہ ضروری نہیں کہ وہ طلاق کی کوئی وجہ بیان کرے.شریعیت
نے وجہ بیان نہ کرنے کی جو آزادی دی ہے اس میں عظیم مصلحتیں ہیں کیونکہ شارع کا منشاء یہ ہے کہ
سے سورۃ النساء آیت ۳۶
Page 77
طلاق اگر ناگزیر ہی ہو جائے تو نا چاقی کی وجوہات کو منظر عام پر لائے بغیر ہی طلاق دی جاوے تا کہ
عورت کے مزعومہ نقائص یا کمزوریوں کا چرچہ نہ ہو.دفعہ نمبر ۳۳
صحت طلاق اور اس کے موثر ہونے کے لئے مندرجہ ذیل تین شرائط ہیں
د طلاق ہوش و حواس کی حالت میں پوری سوچ بچار کے بعد اپنی مرضی سے دی جائے.جلد بازی، غصہ اور جبر کے تحت دی گئی طلاق موثر نہ ہو گی ہے
ب - طلاق ایسے طہر میں دی جائے جس میں خاوند نے اپنی بیوی سے مباشرت نہ کی ہو حیض کی حالت
میں دی گئی طلاق موثر نہ ہو گی.ج - زبانی یا تحریری طلاق کی اطلاع بیوی کو مل جائے قضا طلاق کا عمل اس وقت سے شروع ہوگا
جب بیوی کو اس کی اطلاع ملی ہو اور اسی وقت سے عورت کی عدت شروع ہوگئی ہے
ے بعض فقہاء نے غصہ، جلد بازی اور جبر کی طلاق کو مونثر مانا ہے.اسی طرح یہ بھی ضروری قرار نہیں دیا کہ طلاق کی اطلاع بیوی کو دی جائے لیکن فقہ احمدیہ فقہاء
کی اس رائے کو درست تسلیم نہیں کرتی تفصیل کے لئے دیکھیں بداية المجتھد میت -
كتاب الفقه على المذاهب الاربعه ص.
Page 78
وقعہ نمبر ۳۴
طلاق کا ثبوت یا تو میاں بیوی دونوں کے اقرار سے ہوگا یا گواہوں کی
گواہی سے مستند تحرر بھی گواہی کے قائمقام سمجھی جاسکتی ہے.ه
دفعہ نمبر ۲۵
قابل رجوع یا قطعی ہونے کے لحاظ سے طلاق کے تین درجے ہیں.د طلاق رجعی - ب - طلاق بائن
ج - طلاق بتہ
تشریح : جیسا کہ پہلے وضاحت آچکی ہے کہ طلاق " ابغض الحلال ہونے کی وجہ سے ایک
انتہائی ناپسندیدہ فعل اور ایک ناگزیر برائی ہے.اس لئے اس منزل تک پہنچنے سے پہلے انتہائی سوچ بچار
کر لینا ضروری ہے.اسی لئے شریعت نے تحکیم کی ہدایت کی ہے اور تحکیم کے بعد اگر علیحد گی ضروری ٹھہرے
تو بھی اس نازک تعلق کو ہمیشہ کے لئے ختم کرنے سے پہلے مرد کو بار بار سوچ بچار کرنے کے مواقع مہیا کئے
ہیں اور اسی لئے الگ الگ وقتوں میں تین طلاق دینے کی رعایت خاوند کو دی گئی ہے.طلاق رجعی
طلاق رجعی وہ طلاق ہے جس میں عدت کے دوران خاوند رجوع
کر سکتا ہے مثلاً ایسے ایام میں
ه ابوداؤد کتاب الطلاق باب في كراهية الطلاق ص19
عدت کی تفصیل کے لئے دیکھیں دفعہ نمبر ۴۳ -
من
Page 79
جب کہ عورت حالت طہر میں ہو مرد صرف ایک طلاق دے.اس طلاق کے بعد خاوند عدت کے اندر
بغیر کسی زائد شرط کے رجوع کر سکتا ہے یعنی اس طلاق کو واپس لے سکتا ہے اور عورت کو حسب سابق
اپنی بیوی کے طور پر رکھ سکتا ہے.طلاق بائن
طلاق بائن وہ طلاق ہے جس میں خاوند رجوع تو نہیں کر سکتا البتہ عدت کے دوران یا عدت
کے بعد بیوی کی رضامندی سے دوبارہ نکاح کر سکتا ہے.مثلاً نکاح کے بعد قبل از رخصتانہ و خلوتِ
صحیحہ طلاق دے یا بیوی کی طرف سے مالی معاوضہ لے کر اسے طلاق دے یا طلاق رجعی کے بعد عدت
گذر جائے تو طلاق کی ان سب صورتوں کو طلاق بائن کہتے ہیں.طلاق به
طلاق بتہ وہ طلاق ہے جس میں نہ رجوع ہو سکتا ہے نہ دوبارہ نکاح جائز ہے گویا یہ طلاق
فریقین کے درمیان قطعی تفریق کا باعث بن جاتی ہے اور ایسی ہی طلاق پر " حَتَّى تُنْكِحَ زَوْجًا
غيرة کی پابندی عائد ہوتی ہے.تشریح
طلاق کی ان تینوں قسموں کی تشریح علی الترتیب درج ذیل ہے:.د - طلاق بھی :- طلاق کے حق کو استعمال کرنے کے بارہ میں اسلام کی اصولی ہدا
ہے کہ مرد عورت کے طہر کے ایام میں صرف ایک طلاق دے اس کے نتیجہ میں تین قروء یعنی تین
حیض عدت گزرنے کے دوران اگر خاوند چاہے تو وہ بغیر کسی شرعی روک کے رجوع کر سکتا ہے لیے
اور عدت گزرنے کے بعد گو علیحدگی مکمل ہو جائے گی، لیکن اگر یہ دونوں چاہیں تو باہمی رضا مندی
سے دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں.اس طرح طلاق دے کر اس کے بعد عدت کے اندر رجوع کرنے کا حق آیات قرآنی کی روشنی
وبعولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِهِنَ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا اصلاحا (سورۃ البقره آیت ۲۲۹)
Page 80
میں دو مرتبہ ہے لیئے
غرض جن حالات میں طلاق دے کہ رجوع کرنے کا حق باقی رہے ان حالات میں دی گئی طلاق کوفتہ
کی اصطلاح میں طلاق رجعی " کہتے ہیں.طلاق رجعی کے بعد عدت کے دوران میں خاوند کو یہ حق ہے کہ وہ طلاق واپس لے لے جیسا کہ
رمایا:
:-
وبعولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَةِ هِنَ فِي ذلِكَ إِنْ أَرَادُوا صَلَاحًا
اس لحاظ سے مرد کا ایک طرفہ طور پر طلاق واپس لے لینا ہی رجوع کے لئے کافی ہے کیونکہ ابھی
سابقہ نکاح قائم ہے اور بجلی انقطاع نہیں ہوا.رجعی طلاق گویا ایک معلق طلاق ہے.عدت کے
دوران اسے واپس لیا جا سکتا ہے، لیکن عدت گزرنے کے بعد یہی طلاق بائن ہو جائے گی.ب - طلاق بائن : وہ طلاق ہے جس کے نتیجہ میں طلاق واقع ہو جاتی ہے اور خاوند کو عدت
کے اندر رجوع کا حق باقی نہیں رہتا البتہ باہمی رضا مندی سے عدت کے دوران اور عدت گزرنے
کے بعد دونوں صورتوں میں دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے.مثلاً قبل از رخصتانه یعنی مباشرت کا موقع ملنے
سے پہلے طلاق دینا "بائن طلاق کے حکم میں ہے.فقہاء نے خلع، مہارا کیے اور فسخ نکاح کو بھی طلاق
بائن نے حکم میں رکھا ہے یہ اسی طرح رجعی طلاق عدت گذرنے کے بعد طلاق بائن بن جاتی ہے اس قسم
کی طلاق کے بعد نیا نکاح ہو سکتا ہے.ج - طلاق بتہ :- احکام قرآنی کے مطابق نکاح کے نتیجہ میں مرد کو تین طلاق کا حق ملتا ہے.یہ حق
کس طرح استعمال کیا جاسکتا ہے.اس بارہ میں فقہاء کے تین مسلک ہیں :-
ا.ایک مسلک یہ ہے کہ مرد کو اختیار ہے کہ وہ یہ حق جس طرح چاہیے.استعمال کرے چاہے تو
بیک وقت یہ کہہ کر اپنا حق استعمال کرلے کہ " تجھے تین طلاق یا تجھے طلاق، تجھے طلاق ، تجھے طلاق.یا
وقفہ وقفہ کے بعد الگ الگ اوقات میں تین بار یہ حق استعمال کرے ہر طرح اسے اختیار ہے.ه الطَّلَاقُ مَرَتْنِ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُونٍ اَوْ تَسْرِيحُ بِاِحْسَانِ (سورة البقره آیت ۲۳۰)
کے سورة البقره آیت ۲۲۹
مبارات : اظہار برات، بے زاری کا اظہار
که تفصیل کے لئے دیکھیں دفعہ نمبر ۴۴
Page 81
دوسرا مسلک یہ ہے کہ مرد یہ حق تین الگ الگ طہروں میں استعمال کر سکتا ہے مثلاً پہلے طہر میں پہلی
طلاق دے، دوسرے طہر میں دوسری اور تیسرے طہر میں تیسری.اس طرح تین طلاقیں واقع ہو جائیں گی
اور دونوں (مرد اور عورت) میں دائمی فرقت ہو جائے گی.-۳- تیسرا مسلک یہ ہے کہ مرد اپنا یہ حق استعمال کرنے میں آزاد نہیں بلکہ وہ بعض مخصوص شراللہ کے
تحت ہی یہ حق استعمال کر سکتا ہے.اس اختلاف کے باوجود تمام علماء امت کے نزدیک اسلام یہ پسند
کرتا ہے اور اسے ترجیح دیتا ہے کہ خاوند کو تین طلاق دینے کا جو حق دیا گیا ہے وہ اسے بڑی احتیاط
کے ساتھ استعمال کرے یعنی صرف ایک طلاق دے.اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ عدت کے اندر وہ رجوع کر
سکے گا اور عدت کے بعد باہمی رضا مندی سے ان کا دوبارہ نکاح ہو سکے گا.مرد کے طلاق دینے اور
اس سے رجوع کرنے کے مسئلے پر پیش آنے والی مختلف صورتوں کو سامنے رکھ کر فقہاء نے مختلف فتوے
دیتے ہیں.بعض فقہاء نے مرد کے رجوع کے حق کو زیادہ پابند کیا ہے اور بعض فقہاء نے اس بارہ میں
سہولت کو مد نظر رکھا ہے تا کہ میاں بیوی کا تعلق جو ظور میں آچکا ہے اسے حتی الامکان قائم رکھا جائے.فقہ احمدیہ نے سہولت کے طریق کار
کو ترجیح دی ہے.فقہ احمدیہ کی رو سے ہر ممکن کوشش اس
امر کی ہونی چاہیئے کہ فریقین اگر مائل بہ اصلاح ہوں اور وہ نکاح کو قائم رکھ سکیں تو اس سلسلہ میں
شریعت کے اصل منشاء کو پیش نظر رکھا جائے جو یہ ہے کہ زوجین کے تعلق کو قطعی طور پر ختم کرنے سے
پہلے ہر ممکن موقع رجوع کا دیا جائے.جماعت احمدیہ کا یہ مسلک قرآن و حدیث کے مختلف احکام کے عین مطابق ہے اور اس مسلک کی
سنا فقہائے سلف سے بھی ملتی ہے.حق طلاق کے استعمال پر پابندی کی ایک مثال یہ ہے کہ کوئی شخص تین طلاق کا حق ایک ہی دفعہ
استعمال کرے.فقہائے صنفی کے نزدیک اگر اس طرح ایک ہی نشست میں تین طلاقیں دے دی جائیں تو
تمینوں واقع ہو جاتی ہیں گویا طلاق بتہ یعنی قطعی طلاق وقوع میں آجاتی ہے اور مرد کو رجوع یا دوبارہ نکاح
کا حق حاصل نہیں رہتا.لیکن فقہ احمدیہ اس طرح ایک نشست میں تین طلاق کے استعمال اور اس کے اس اثر کو تسلیم
نہیں کرتی اور اس بات پر زور دیتی ہے کہ جس بات کو شریعت نے تین بار پر موقوف کیا ہے وہ تین
ان مخصوص شرائط کی تفصیل آئندہ صفحات میں ملاحظہ فرماویں.
Page 82
مختلف اوقات میں ہی ہونی چاہئیے کیونکہ قرآن کریم میں ارشاد ہے:.الطَّلَاقُ مَرَّتَنِ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُونِ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ له
یعنی ایسی طلاق جس میں رجوع ہو سکے دو دفعہ ہو سکتی ہے پھر یا تو مناسب طور پر روک لینا
ہو گا یا حسن سلوک کے ساتھ تیسری طلاق دے کر رخصت کر دینا ہو گا.1 - اِس آیت سے پہلے ارشاد باری ہے :-
وَالْمُطَلَقْتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلتَةَ قُرَوا ہے یعنی جن عورتوں کو طلاق مل جائے وہ تین
بار حیض آنے تک اپنے آپ کو روک رکھیں جس کا درمان مطلب یہ ہے کہ آیت " الطَّلَاقُ مرتنِ من الطَّلَاقِ
سے اشارہ اسی المُطَلَّقْتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُو کی طرف ہے اور مطلب یہ ہے کہ ایک
ایسی عورت جس کو ایک طلاق دی گئی ہو اور وہ عدت گزار رہی ہو خاوند کو حق ہے کہ وہ عدت تین قروء
یا تین ماہ کے اندر رجوع کرلے اور اگر عدت گزر جائے تو باہمی رضامندی سے نیا نکاح کرلے.اس
رجوع یا دوسرے نکاح کے بعد اگر وہ پھر طلاق دے دے تو خاوند کو ایک بار پھر عدت کے اندر رجوع
کرنے اور عدت گزرنے کے بعد باہمی رضا مندی سے نیا نکاح کرنے کا حق ہوگا اس دوسرے رجوع یا
تیسرے نکاح کے بعد اگر وہ پھر طلاق دے گا تو اس تیسری طلاق کے بعد عدت کے اندر نہ وہ رجوع
کر سکے گا اور نہ عدت کے بعد باہمی رضامندی سے نیا نکاح کر سکے گا جب تک کہ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا
غيرہ اس کی شرط پوری نہ ہو.آیت کریمہ الطلاق مرشنِ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُونِ أَوْ تَشْرِيمَ بِإِحْسَانٍ
میں اسی انداز سے دی ہوئی تین طلاقوں کا ذکر ہے.ވ ހ
ب - آیت میں مرتین" کا لفظ دو الگ الگ موقعوں پر طلاق دینے کا متقاضی ہے سوال یہ ہے کہ وہ
الگ الگ مواقع کون سے ہیں.یہی مقام قابل غور ہے.صاحب نیل الاوطار لکھتے ہیں :-
الظَّاهِرَانَ الطَّلَاقَ المَشْرُوعَ لَا يَكُونُ بِالثَّلَاثِ دَفْعَةً بَلْ عَلَى التَّرْتِيْبِ
الْمَذْكُورِ وَهذَا اظْهَرُ
لے سورة البقره آیت ۲۳۰
سے سورۃ البقرہ آیت ۲۳۱
سورة البقره آیت ۲۲۹
که نیل الاوطار كتاب الطلاق باب ما جاء في طلاق البتة الخصم
Page 83
یعنی مسئلہ طلاق کے بارہ میں جو احادیث مروی ہیں ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایک ہی دفعہ تین
طلاقیں دینے سے تین طلاقیں نہیں پڑتیں بلکہ قرآن و حدیث میں مذکور ترتیب کے مطابق طلاق دینے کی
ہدایت کی پابندی ضروری ہے اور یہی مسلک زیادہ واضح اور صحیح ہے.گویا احکام قرآنی اور ارشادات نبوی کے مطابق اٹھی تین طلاقیں دینا مشروع نہیں ہے لہذا فقہ
احمدیہ کے نزدیک اگر تین طلاقیں ایک دفعہ ہی دے دی جائیں تو ایک رجعی طلاق منصور ہو گی.ایک صحابی حضرت رکا نہ نے ایک مجلس میں اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دیں جس کا اسے بعد میں
احساس ہوا.جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ معاملہ پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا
کہ اس نے طلاق کس طرح دی تھی.اس نے بتایا کہ ایک ہی مجلس میں اس نے تین طلاقیں دے دی تھیں
اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح تو ایک طلاق واقع ہوتی ہے تم رجوع کر لویہ
یہ بات مستند روایات سے ثابت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر کے سارے
عہد خلافت اور حضرت عمر ض کے عہد خلافت کے ابتدائی دور میں ایک مجلس میں دی گئی تین طلاقیں ایک طلاق
متصور ہوتی تھیں لیکن حضرت عمریض نے جب یہ محسوس فرمایا کہ شریعت کی دی گئی ایک سہولت کو بعض نادان
وگوں نے مذاق بنا لیا ہے تو حکم صادر فرمایا کہ لوگوں کی اس جلد بازی پر گرفت کی جائے اور اس طرح کی
دی ہوئی تین طلاقوں کو تین ہی متصور کیا جائے تاکہ لوگوں کو تنبیہہ ہو گئے
مگر حضرت عمر کا یہ حکم تعزیر کارنگ رکھتا ہے اور اسے دائمی حکم قرار نہیں دیا جاسکتا.علاوہ ازیں
جن فقہاء نے ایک نشست میں تین طلاقوں کو تیں تسلیم کیا ہے وہ بھی ایسی طلاق کو طلاق بدعت کا نام
دیتے ہیں گویا اس کا ناپسندیدہ ہونا ان کے نزدیک بھی مسلم ہے.پس فقہ احمدیہ اس بدعت کو شرعی
حیثیت نہیں دیتی ہے کہ ایک نشست میں اس طرح دی گئی تین طلاقوں کے بعد اگر کوئی شخص پشیمان
ہو اور رجوع کرنا چاہے تو اس کے رجوع کے حق کو تسلیم کیا جائے گا.حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں :-
اگر تین طلاق ایک ہی وقت میں دی گئی ہوں تو اس خاوند کو یہ فائدہ دیا گیا ہے کہ
وہ عدت کے گذرنے کے بعد بھی اس عورت سے نکاح کر سکتا ہے کیونکہ یہ طلاق نا جائزہ
له مسند احمد ۲۶۵ - دار قطنی من - نیل الاوطار ص
صحیح مسلم مصری کتاب الطلاق باب طلاق الثلاث ما
Page 84
طلاق تھا اور اللہ و رسول کے فرمان کے موافق نہ دیا گیا تھا.دراصل قرآن شریف
میں غور کرنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کو یہ امر نہایت ہی ناگوار ہے کہ
پرانے تعلقات والے خاوند اور بیوی آپس کے تعلقات کو چھوڑ کر الگ الگ ہو جائیں
نہی وجہ ہے کہ اس نے طلاق کے واسطے بڑے بڑے شرائط لگائے ہیں.وقفہ کے بعد
تین طلاق کا دینا اور ان کا ایک ہی جگہ رہنا وغیرہ یہ امور سب اس واسطے ہیں کہ شاید کسی
وقت ان کے دلی رنج دور ہو کہ آپس میں صلح ہو جائے.....خدا تعالیٰ فرماتا ہے
" الطَّلَاقُ مَرتُنِ» یعنی دو دفعہ کی طلاق ہونے کے بعد یا اسے اچھی طرح سے رکھ لیا
جائے یا احسان سے جدا کر دیا جائے.اگر اتنے لمبے عرصے میں ان کی آپس میں صلح نہیں ہوتی تو پھر
ممکن نہیں کہ وہ اصلاح پذیر ہیں یا لے
بہر حال فقہ احمدیہ کے نزدیک تین طلاقوں کا حق یا تو دور بھی اور ایک بائن طلاق کی صورت
میں استعمال ہوگا یا تین بائن طلاقوں کی صورت میں جس کی شکل یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو ایک طلاق
رجعی دے پھر عدت کے دوران رجوع کرے تو وہ ایک طلاق واقع ہو جائے گی اس کے بعد اگر وہ دوبار
طلاق ریجی دے اور پھر عدت کے اندر رجوع کرے تو یہ اس کی طرف سے دوسری طلاق واقع شدہ شمار
ہو جائے گی.اب اس کے بعد جب تیسری مرتبہ طلاق دے گا تو وہ " طلاق بنہ ہو گی یعنی عدت کے
اندر رجوع کرنے اور عدت کے بعد نکاح کرنے کا حق باقی نہیں رہے گا کیونکہ وہ اپنا طلاق دینے کا حق
تین مرتبہ استعمال کر چکا ہے.دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق رجعی دے اور عدت کے دوران رجوع
نہ کرے اس صورت میں عدت گزرنے کے بعد ایک طلاق بائن “ ہو گی لیے اب وہ رجوع تو نہیں کر
سکتا مگر دوبارہ نیا نکاح کر سکتا ہے.اس دوسرے نکاح کے بعد اسے طلاق کا حتی تین مرتبہ نہیں بلکہ
صرف دو مرتبہ حاصل ہو گا لہذا اگر وہ اب طلاق دے اور رجوع نہ کرے اور عدت گذر جائے تو یہ
اس کی طرف سے دوسری طلاق بائن ہوگی.اس کے بعد وہ پھر باہمی رضامندی سے نکاح کر سکتے ہیں
یہ ان کا تیسرا نکاح ہو گا جس کے نتیجہ میں صرف ایک باقی طلاق کا حق اسے ملے گا یعنی اگر وہ اطلاق
الحكم جلد ۱۳ مورخه در اپریل ۶۱۹۰۳ ص
که یا مثلاً قبل از رخصتانہ طلاق دے جو بائن ہوتی ہے.
Page 85
دے گا تو یہ اس کی " طلاق بستہ ہوگی اور دونوں میں قطعی جدائی ہو جائے گی نہ رجوع ہو سکے گا اور
نہ دوبارہ نکاح - گویا طلاق بتہ کے واقع ہونے کے لئے دو طلاقوں کے درمیان یا تو رجوع حائل ہونا
چاہیے یا دوسرا نکاح.اگر ان دونوں صورتوں میں سے کوئی بھی صورت نہیں تو خواہ کتنی بار وہ منہ
سے طلاق کا لفظ بولے طلاق ایک ہی متصور ہوگی.اس مسلک کو فقہاء سلف میں سے بھی بعض (مثلاً
امام شوکانی وغیرہ نے تسلیم کیا ہے اور اسے ” طلاق مغلظہ“ کا نام دیا ہے یہ
طلاق بتہ کے بارہ میں یہ نظریہ اگرچہ فقہائے احناف کے مسلک کے خلاف ہے لیکن فقہ احمدیہ
آیات قرآنی اور احادیث الرسول اور بعض ائمہ سلف اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے
جانشینوں لے کے احکام کی روشنی میں اسی بات کی قائل ہے کہ طلاق بائن کے بعد فریقین آپس میں دوبارہ
نکاح کر سکتے ہیں سوائے اس کے کہ طلاق تیسری مرتبہ بائن ہو جائے اور اسی کو طلاق بتہ یا طلاق
له روضة النديه شرح الدرر البهيه كتاب الطلاق طلا
ے سیدنا حضرت مصلح موعود لکھتے ہیں :.عام طور پر اس زمانہ کے علماء یہ مجھتے ہیں کہ جس نے تین دفعہ طلاق کہہ دیا اس کی
طلاق بائن ہو جاتی ہے یعنی اس کی بیوی اس سے دوبارہ اس وقت تک شادی نہیں کر سکتی
جب تک کسی اور سے نکاح نہ کرے مگر یہ غلط ہے کیونکہ قرآن کریم میں صاف فرمایا گیا ہے
الطَّلَاقُ مَرَنِ" یعنی وہ طلاق جو بائن نہیں وہ دو دفعہ ہو سکتی ہے.اس طور پر کہ پہلے مرد
طلاق دے پھر یا طلاق واپس لے لے اور رجوع کرے یا عدت گذرنے دے اور نکاح کرے پھر
ان بن کی صورت میں دوبارہ طلاق دے پیس ایسی طلاق کا دو دفعہ ہونا تو قطعی طور ثابت ہے.پس ایک ہی دفعہ تین یا تین سے زیادہ بار طلاق کہہ دینے کو بائن قرار دینا قرآن کریم کے بالکل
خلاف ہے طلاق وہی بائن ہوتی ہے کہ تین بار مذکورہ بالا طریق کے مطابق طلاق دے اور تین مدیتیں
گزر جائیں اس صورت میں نکاح جائزہ نہیں جب تک کہ وہ عورت کسی اور سے دوبارہ نکاح نہ
کر سے اور اس سے بھی اس کو طلاق نہ مل جائے لیکن ہمارے ملک میں یہ طلاق مذاق ہوگئی ہے اور
اس کا علاج حلالہ جیسی گندی رسم سے نکالا گیا ہے"
تفسیر صغیر زیر آیت سوره بقره ۲۳۰ ایڈیشن ششم مثه )
اس جگہ بائن کا لفظ بينونة کبرای یعنی طلاق بتہ کے معنوں میں استعمال ہوا ہے جیسا کہ بعد کی عبارت سے ظاہر ہے.
Page 86
۸۳
مغلظہ " کہا جاتا ہے اس کے بعد یہ دونوں مرد اور عورت باہمی رضامندی سے بھی آپس میں نکاح نہیں
کرسکتے سوائے اس کے کہ " حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَہ کی قرآنی شرط پوری ہو یعنی عورت اپنی مرضی سے
کسی دوسرے شخص سے شادی کرے اور پھر خاوند کے فوت ہو جانے یا کیسی اور قدرتی وجہ سے وہ عورت
اس نکاح سے آزاد ہو جائے اور پھر وہ پہلے خاوند سے نکاح کرنے پر راضی ہو تو اس طرح یہ دونوں
پھر سے میاں بیوی بن سکیں گے.O.ے قدرتی وجہ کی شرط اس لئے بیان ہوئی ہے کہ حلالہ کے طریق کی خرابی اور اس کے بطلان
کو واضح کیا جائے " حلالہ کا رواج بعض مسلمان فرقوں میں ہے اور اس کی صورت یہ
بیان کی جاتی ہے کہ کسی شخص نے غصہ میں آکر یا نا سمجھی سے جلد بازی میں اپنی بیوی کو تین
طلاقیں اکٹھی دے دیں اس کے بعد دونوں پچھتائے اور آپس میں پھر سے نکاح کرنے کا
ارادہ کیا لیکن چونکہ ان فرقوں کے نزدیک طلاق بتہ واقع ہو چکی ہے اور حتی تنكِحَ زَوْجًا
غیرہ کی شرط پوری کئے بغیر وہ آپس میں دوبارہ نکاح نہیں کر سکتے اس لئے کسی مرد کو تیار کیا
جاتا ہے کہ وہ اس عورت سے نکاح کرے اور پھر مباشرت کے بعد اسے طلاق دے دے تاکہ
وہ عورت اپنے پہلے خاوند سے نکاح کر سکے.اس مصنوعی اور بے شرمی کے طریق کی اسلام نے
ہرگز اجازت نہیں دی.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لعن الله المُحلل
والمحلل له - ( ابوداؤد كتاب النكاح باب في التحليل م )
Page 87
ادو
دفعہ نمبر ۳۶
اگر علیحدگی کا مطالبہ عورت کی طرف سے ہوا اور وہ نکاح سے آزاد ہونے پر
مصر ہوا اور مرد طلاق دینے سے انکار کرے تو عورت اپنے حق مہر یا دیگر مالی
منفعت کے عوض قاضی کے ذریعہ خلع حاصل کر سکتی ہے.تشریح : خلع کے بارہ میں قرآن مجید میں ارشاد ہے :-
وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا أَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَا فَا الايقِيْمَا
حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ الَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا
افْتَدَتْ بها
یعنی تمہیں اگر اندیشہ ہو کہ میاں بیوی کے کشیدہ تعلقات اب اس مرحلہ پر پہنچے گئے
ہیں کہ ان میں نباہ نہیں ہو سکے گا اور وہ دونوں حدود اللہ کو قائم نہیں رکھ سکیں گے
اور عورت علیحدگی پر مصر اور فدیہ یعنی بدل ضلع دینے پر آمادہ ہو تو بیوی کے بدل ضلع
دینے اور میاں کے لینے میں کوئی گناہ نہیں.تم انہیں اس طرح علیحدہ ہونے کی اجازت
دے دو.اِس فرمان کی مزید تشریح مختلف احادیث اور خلفائے راشدین کے عمل سے ہوتی ہے چنانچہ
ایک حدیث میں آتا ہے کہ جمیلہ بنت سلول " آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض
کیا کہ مجھے اپنے خاوند ثابت بن قیس کی دینداری اور خوش خلقی پر کوئی اعتراض نہیں لیکن میری طبیعت
له سورة البقره آیت ۲۳۰
Page 88
۸۵
اس سے نہیں ملتی اور اس وجہ سے مجھے اس سے سخت نفرت ہے.پس ایسے حالات ہیں لیکن اس کے
حقوق ادا نہیں کر سکوں گی اور ناشکری کی مرتکب ہوں گی اِس لئے مجھے علیحدگی دلوائی جائے.آپ نے فرمایا کیا مہر میں لیا ہوا باغ واپس کرنے کو تیار ہو.اس نے عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ
بلکہ اس سے زیادہ بھی.آپ نے فرما یا مصر میں لیا ہوا باغیچہ واپس کر دو اس سے زیادہ نہیں ہے
مذکورہ بالا ارشاد سے خلع کے سلسلہ میں حسب ذیل پہلو واضح ہوتے ہیں :.: جس طرح طلاق کے ذریعہ میاں کو علیحدگی کا اختیار حاصل ہے اسی طرح ضلع کے ذریعہ
بیوی
کو علیحد گی طلب کرنے کا اختیار حاصل ہے.ب : خلع کی صورت میں بیوی کی علیحدگی کے لئے ضروری ہے کہ وہ قاضی کے سامنے اپنا معاملہ
پیش کرے اور اس کی مدد سے علیحدگی اختیار کرے.ج : خلع کی صورت میں بیوی کو وہ مالی مفادات واپس کرنے ہوں گے جو وہ اپنے میاں سے
حاصل کر چکی ہے اس کی واضح مثال مہر کی واپسی ہے.- میاں خواہ راضی ہو یا راضی نہ ہو بیوی کے اصرار کی صورت میں قاضی ان دونوں کے
در میان علیحدگی کا حکم صادر کر سکتا ہے ایسی علیحدگی کو ضلع کہتے ہیں.ل : خلع کی عدت صرف ایک حیض ہے یا وضع حمل ہے ہے.و :.نفس ضلع کے لحاظ سے عورت کو ضلع طلب کرنے کا ایسا ہی حق ہے جیسا مرد کو طلاق دینے
کا حق ہے جس طرح کوئی شخص مرد کو طلاق دینے سے روک نہیں سکتا اسی طرح کوئی شخص عورت کو
خلع لینے سے بھی نہیں روک سکتا.علامہ ابن رشد کا یہی مسلک تھا.چنانچہ وہ ضلع پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں :.خلع عورت کے اختیار میں ہے بمقابلہ مرد کے اختیار طلاق کے جس میں وہ مختار
ہے.جب عورت کو مرد کی طرف سے کوئی تکلیف ہو اور اس وجہ سے وہ اسے ناپسند
کرتی ہو تو وہ اپنے حق اختیار ضلع کو استعمال کر کے علیحدگی حاصل کر سکتی ہے
له بخاری کتاب الطلاق باب الخلم جلد ه ص - ابن ماجه باب المختلعة تاخذ ما.۲۴۵
اعطاها مث.دارقطني م۳۹ - نصب الرايه ٣٢.تفصیل کے لئے دیکھیں دفعہ نمبر ۴۳ بحث عدت.
Page 89
۸۶
اس کے بالمقابل جب مرد کو عورت کی طرف سے تکلیف ہو اور وہ اسے نہ چاہتا ہو تو
شارع نے اسے طلاق دینے کا اختیار دیا ہے" لے.ضلع کے لئے بیوی کو اپنا معاملہ قاضی کے سامنے پیش کرنا ضروری ہے.اس کی حکمت
یہ بھی ہے کہ شادی کے موقع پر خاوند کم و بیش بعض مالی ذمہ داریاں اٹھاتا ہے اور
بیوی یا اس کے والدین کے مطالبہ پر وہ بالعموم حق مہر کے علاوہ بھی زائد اخراجات برشاشات
کرتا ہے.اب اگر خاوند سے علیحدگی کے معاملہ میں عورت سراسر زیادتی کی مرتکب ہو رہی
ہوا اور خاوند کا کوئی قصور نہ ہو بلکہ وہ مظلوم ہو تو قاضی اِس بات کو زیر غور لا سکتا ہے
کہ خاوند پر یہ نا واجب مالی بوجھ کیوں پڑے اور کیوں نہ مہر کے علاوہ زائد خرچ بھی
عورت سے واپس دلوایا جائے.اسی طرح اگر عورت مہر وصول کر چکی ہے تو اس کی واپسی کا معاملہ بھی قضاء یا عدالت
حل کر سکتی ہے.لیکن اگر ضلع کے ذریعہ عورت کو بھی مرد کی طرح خود بخود علیحدگی کا اختیار
ہوا اور قاضی سے فیصلہ حاصل کرنا ضروری نہ ہو تو مہر یا دوسری مالی ذمہ داریوں کے بارہ
میں تنازعہ پیدا ہو سکتا ہے.نیز بعض اوقات عورت اپنی ناسمجھی یا نا تجربہ کاری کی وجہ
سے غلط بنیاد پر ضلع کے لئے اصرار کر رہی ہوتی ہے جب معاملہ قاضی کے سامنے آئے گا
تو قاضی کے لئے اس کو سمجھانے یا صورت حال واضح کرنے کا موقع میسر آ سکتا ہے اور
اِس بات
کا بڑی حد تک اِمکان ہے کہ عورت سمجھ جائے اور علیحدگی تک نوبت نہ پہنچے
لیکن اگر عورت خلع لینے پر مصر ہو اور سمجھانے کے باوجود اپنی ضد پر قائم رہے تو قاضی
اس کے مطالبہ پر علیحدگی کا فیصلہ تو صادر کر دے
گا لیکن اگر وہ دیکھے گا کہ عورت ظلم کی
مرتکب ہو رہی ہے اور اس کا رویہ جارحانہ ہے اور خاوند کا کوئی قصور نہیں تو وہ ضلع
کے فیصلہ کے ساتھ یہ شرط بھی عائد کر سکتا ہے کہ خاوند نے عورت یا اس کے والدین کے
مطالبہ پر جو کچھ بھی خرچ کیا ہے وہ خاوند کو واپس کیا جائے.لَمَّا جُعِلَ التَّطلِيقُ بِيَدِ الرَّجُلِ إِذَا فَرِكَ الْمَرْأَةَ جُعِلَ الْخُلُعَ بِيَدِ الْمَرْأَةِ
إذَا فَرِكَتِ الرّجُل.۵۶
( بداية المجتهد كتاب النكاح الباب الثالث في الخُلمِ م ،
Page 90
AL
اور جب تک وہ واپس نہ ہو اس وقت تک ضلع کا فیصلہ ملتوی رہے.۲ - طلاق کی صورت میں خاوند حق مہر اور دیگر تحائف وغیرہ جو وہ دے چکا ہے واپس
لینے کا مجاز نہیں ہوتا لیکن خلع کی صورت میں عورت کو اکثر وہ مالی مفادات چھوڑنے ہونگے
یا واپس کرنے ہوں گے جو وہ خاوند سے حاصل کر چکی ہے.اس سلسلہ میں ثابت بن قیس
"
کی بیوی کا واقعہ بنیادی حیثیت رکھتا ہے جسے صحیح بخاری ، نسائی کے علاوہ دیگر متعدد
محدثین نے بھی بیان کیا ہے.دفعہ نمبر ۳۷
خلع کے فیصلہ کے لئے قاضی کا صرف اِس قدر اطمینان کافی ہے کہ عورت
خود اپنی آزادانہ رائے سے ضلع چاہتی ہے.ضلع کے مطالبہ کے لئے کسی اور
وجہ کا اظہار یا ثبوت لازمی نہ ہوگا.تشریح :- وجوہات ضلع میں صرف یہ وجہ کافی ہے کہ عورت کہے کہ وہ اپنے خاوند کے پاس رہنا یا اگر
رخصتانہ نہیں ہوا تو اس کے پاس جانا پسند نہیں کرتی اور اسے اپنے خاوند سے نفرت ہے.نفرت کی
وجوہات ظاہر کرنے کی وہ پابند نہیں.صاحب نیل الاوطار احادیث ضلع پر بحث کرتے ہوئے بطور خلاصہ لکھتے ہیں :-
ظَاهِرُ أَحَادِيثِ الْبَابِ اَنَّ مُجْرَدَ وَجُودِ الشَّقَاقِ مِنْ قِبَلِ الْمَرْأَةِ كَانِ
فِي جَوَازِ الْخُلُعِ
له بخاری کتاب الطلاق باب الخلع جلد ۲
له نيل الأوطار كتاب الخلع م
Y
۷۹۴
Page 91
A A
یعنی احادیث ضلع پر غور کرنے سے ثابت ہوتا ہے کہ جو از خلع کے لئے صرف یہ وجعہ کافی ہے
کہ میاں بیوی میں افتراق اور نا چاتی ہے اور وہ اب مل کر نہیں رہ سکتے.قضاء کی طرف سے بعض اوقات خلع کی درخواست کے تسلیم کرنے میں جو بظا ہر ترقد کیا جاتا ہے
اس کا مقصد در حقیقت درخواست ضلع کو رو کرنا نہیں ہوتا بلکہ اس سے صرف یہ کوشش مقصود ہوتی ہے
که کیسی طرح یہ رشتہ قائم رہے اور عورت خاوند کے ساتھ رہنے پر رضامند ہو جائے.جلد بازی ، کسی
کے اکسانے یا وقتی جذبات اس کی چند کا موجب نہ ہوں گویا صرف مصالحت کی امکانی حد تک کوشش کرنا
مقصود ہے ورنہ مسئلہ کی شرعی حیثیت یہی ہے کہ عورت اگر کسی طرح بھی اپنے مطالبہ سے دستکش نہ ہو
تو پھر ضلع منظور کئے بغیر چارہ نہیں.دفعہ نمبر ۳۸
اگر خاوند کے ظلم و تعدی کی وجہ سے عورت خلع لینے پرمجبور ہوگئی ہو تو قاضی
خلع کی صورت میں اسے اس کا حق مہر بھی دلوا سکتا ہے.تشریح :- جس طرح قاضی کو یہ اختیار ہے کہ وہ دیکھے کہ عورت کسی کے اکسانے کی وجہ سے ضلع
کی درخواست تو نہیں کر رہی یا عورت ظلم کی مرتکب تو نہیں ہو رہی اور اس کا رویہ جارحانہ تو نہیں ہے
اسی طرح قاضی کے لئے یہ دیکھنا بھی ضروری ہے کہ کہیں خاوند عورت کو ضلع لینے پر اس غرض سے تو مجبور
نہیں کر رہا کہ وہ مہر کی ذمہ داری سے بچ جائے گویا عورت کی بجائے خاوند کا رویہ ظالمانہ اور جارحانہ ہے
تو اس صورت میں قاضی کو یہ بھی اختیار ہوگا کہ وہ عورت کے مطالبہ خلع کو منظور کرلے اور اس کے
ساتھ خاوند سے اسے اس کا حق مہر بھی دلوائے.چنانچہ امام مالک اس صورت حال کو واضح کرتے ہوئے لکھتے
ہیں :-
الْمُفْتَدِيَةُ الَّتِي تَقدِى مِنْ زَوْجِهَا إِنَّهُ إِذَا عَلِمَ أَن زَوْجَهَا أَضَرَّ بِهَا
Page 92
۸۹
وَضَيَّقَ عَلَيْهَا وَعُلِمَ اَنَّهُ ظَالِمُ لَهَا مَضَى الطَّلَاقُ وَرُةَ عَلَيْهَا مَالُهَا -
قالَ مَالِكُ فَهَذَا الَّذِي كُنْتُ اَسْمَعُ وَالَّذِي عَلَيْهِ أَمْرُ النَّاسِ عِندَنَا الله
یعنی ضلع لینے والی عورت کے متعلق اگر معلوم ہو کہ اس کے خاوند نے اسے دُکھ
دیا ہے اور اسے خلع لینے پر مجبور کیا ہے اور یہ بات ثابت ہو جائے کہ خاوند اس پر ظلم
کرتا رہا ہے تو قاضی کا فیصلہ ضلع نافذ ہوگا اور اس کا مال جو وہ خاوند کو ادا کر چکی
ہے وہ بھی اسے واپس دلایا جائے گا.امام مالک کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے اساتذہ سے یہی سنتا آیا ہوں اور اسی کے مطابق
علماء مدینہ کا عمل درآمد ہے.اس روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ مرد کی طرف سے ظلم کی صورت میں نہ صرف یہ کہ مرد بدل ضلع
نہیں لے سکتا بلکہ اگر وہ کچھ دے چکا ہے تو اس کی واپسی کا مطالبہ بھی نہیں کر سکتا.بہر حال قاضی کیلئے
خلع کا فیصلہ کرتے وقت ظلم و تعدی کے اس پہلو کو بھی مد نظر رکھنا ضروری ہے.ه
دفعہ نمبر ۳۹
خلع طلاق بائن کے حکم میں ہے یعنی فیصلہ ضلع کے بعد خاوند رجوع تو نہیں
کر سکتا مگر فریقین باہمی رضامندی سے دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں.تشریح:-
جیسا کہ پہلے بیان ہوچکا ہے ضلع ان معنوں میں فسخ نکاح ہے کہ ضلع میں خاوند کی رضامندی
ضروری نہیں ہوتی.بیوی کی طرف سے اظہار نفرت اور علیحدگی کے اصرار کی بناء اور بدل خلع کی ادائیگی
کی شرط پر قاضی دونوں کے درمیان علیحدگی کا فیصلہ صادر کرتا ہے.پس جب قاضی ضلع کا فیصلہ صادر
نے موطا امام مالك كتاب الطلاق ما جاء في الخلع
Page 93
۹۰
کر دیتا ہے تو اس کے بعد خاوند کے رجوع کا اختیار ساقط ہو جاتا ہے.صاحب ہدایہ نے اس کی حکمت کو ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے :-
وكَانَ اللقُ بَائِنَا لأَنَّهُ مُعَاوِضَةَ الْمَالِ بِالنَّفْسِ وَقَدْ مَلِكَ الزَّوْجُ
اَحَدَ الْبَدَ لَيْنِ فَتَمْلِكُ هِيَ الأَخِرَ وَهُوَ النَّفْسُ تَحْقِيقًا لِلْمُسَاوَاة له
یعنی بدل خلع کی ادائیگی کی شرط پر یہ علیحدگی طلاق بائن کے حکم میں ہوگی کیونکہ اس
میں نفس کے بدلہ میں مالی بطور معاوضہ ادا کیا جاتا ہے.پس جب خاوند دو چیزوں
میں سے ایک کا مالک ہو گیا یعنی مال کا، تو عورت دوسری چیز کی مالک ہو گئی یعنی اپنے نفس
کی اور اس طرح ان دونوں کے درمیان مساوات کا اصول کار فرما ہوا.وقعہ نمبر ۰ ۴۰
ه
خیار ملبوغ
نابالغ لڑکی جس کے باپ یا ولی مجاز نے اس کا نکاح کر دیا ہو بالغ ہونے پر
اس نکاح کو رد کر دینے کا اختیار رکھتی ہے.اس اختیار کا نفاذ قاضی شے
ذریعہ ہو گا.تشریح : - خیار بلوغ کا مسئلہ کسی نقص صریح سے ثابت نہیں ہے بلکہ اس مسئلے کی بنیا دقیاس پر
نفیق
ہے جو فقہ احمدیہ کا ایک مسلمہ ماخذ ہے.جہاں تک قرآن وحدیث کا تعلق ہے کوئی واضح نص اِس بارہ
له هدايه باب الخلع طي
Page 94
۹۱
میں نہیں ملتی کہ کسی نابالغ لڑکی کا نکاح اس کی بلوغت کے بعد حق استرداد استعمال کرنے پر توڑ دیا
گیا ہو البتہ بالغ لڑکی کے نکاح کا ایک واقعہ احادیث میں مذکور ہے کہ اس کے والد نے اس کا نکاح کر
دیا تھا مگر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں
اس نکاح کو پسند نہیں کرتی تو آپؐ نے اسے اختیار دیا کہ اگر وہ اسے پسند نہیں کرتی تو وہ اس نکاح کو
نامنظور
کر دے.حدیث کے الفاظ یہ ہیں :-
اِنَّ جَارِيَةً بِكْرًا اَتَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ أَنَّ آبَاهَا
زَوْجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ نَخَيَرهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - له
یعنی ایک کنواری لڑکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور
اس نے عرض کی یا رسول اللہ اس کے باپ نے اس کا نکاح کر دیا ہے اور وہ اسے
ناپسند ہے اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اختیار دیا کہ وہ چاہے تو اس
نکاح کو نامنظور کر دے.اس واقعہ پر یہ قیاس کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے معاملہ میں لڑکی
کی رضا کو بھی ضروری سمجھا ہے.پس کوئی وجہ نہیں کہ ایک نابالغ لڑکی کے نکاح کو جبکہ وہ بالغ ہونے
کے بعد اسے رہوکرتی ہے جبراً قائم رکھا جائے چنانچہ حضرت خلیفہ اسیح الثانی
نے اپنے ایک قضائی فیصلہ میں یہ حکم صادر فرمایا :-
"میرے نزدیک لڑکی کو شریعت نے رضا کا حق دیا ہے اور جب وہ بالغ ہو جائے
اس وقت اس کا حق اس کو مل جائے گا.کوئی نکاح کرے.لڑکی بالغ ہو کر اس حق کو جو
اسے خدا تعالیٰ نے اپنے رسول کی معرفت دیا ہے طلب کر سکتی ہے اور کوئی انسانی فقہ
اس حق کو اس سے چھین نہیں سکتی.گورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قسم کی
روایات ثابت نہیں کہ نابالغ لڑکی کا نکاح ماں باپ نے کر دیا اور آپؐ نے لڑکی کی
درخواست پر اسے توڑ دیا ہو، لیکن یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بالغ لوڈ کی کا نکاح اسکے
باپ نے بلا اس کی اجازت کے کر دیا اور آپؐ نے اسے توڑ دیا.پس جب کہ رسول
اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکی کی رضا کو ایسا ضروری سمجھا کہ اس کی فریاد پر باپ کے کئے
۲۸۵
ابو داؤد كتاب النکاح باب البكريزوجها ابوها ما
Page 95
۹۲
ہوئے نکاح کو توڑ دیا تو کوئی وجہ نہیں کہ اس حق کو نکاح نا بالغی کی وجہ سے باطل کر دیا
جائے یا اے
خیار بلوغ کے حق کی بنیاد ہی یہ ہے کہ نکاح میں فریقین یعنی مرد و عورت دونوں
کی رضا ضروری ہے اور نابالغ اپنی عدم بلوغت کی بناء پر رضا کا اہل نہیں ہے لہذا جب
اسے اہمیت حاصل ہو جائے تو وہ حق جسے شریعت نے تسلیم کیا ہے اس کے استعمال
کا اختیار اسے حاصل ہو جاتا ہے.بعض فقہاء نے خیار بلوغ کا حق صرف اس صورت میں
تسلیم کیا ہے جب نابالغ کا نکاح باپ دادا کے علاوہ کسی اور نے کروایا ہو مگر اس
تخصیص کی کوئی بنیا دیا معقول وجہ نہیں اگر نا بالغ کے نکاح کو رد کرنے کا اختیار بعد
حصول بلوغت اس وجہ سے ہے کہ نابالغی کی حالت میں وہ رضا کا اہل نہیں تھا تو کوئی
وجہ نہیں کہ وہی صورت باپ دادا کے کئے ہوئے نکاح میں خیار بلوغ کا باعث نہ بنے
چنانچہ امام ابو یوسف اور امام محمد کے نزدیک خواہ باپ ہو یا دادا جب انہوں
نے نکاح نامناسب مہر پر کیا ہو یا غیر کفو میں کر دیا ہو تو لڑ کی بالغ ہونے پر شیبار
بلوغ کا حق استعمال کر سکتی ہے " کے
کرسکتی
رفقہ احمد یہ خیار بلوغ کے حق کو زیادہ وسیع طور پر تسلیم کرتی ہے نا بالغہ کا نکاح خواہ کسی
نے کروایا ہو بالغ ہونے کے بعد وہ اسے رو کر سکتی ہے.اس بارہ میں حضرت خلیفہ ایسیح الثانی
کا ارشاد ہے :." لڑکیوں کی شادی اس عمر میں جائز ہونی چاہئیے جبکہ وہ اپنے نفع اور نقصان
کو سمجھ سکیں
اور اسلامی حکم یہی ہے کہ شادی عورت کی رضا مندی کے ساتھ ہونی چاہیے اور
جب تک عورت اس عمر کو نہ پہنچ جائے کہ وہ اپنے نفع و نقصان کو سمجھ سکے اس وقت تک
اس کی رضامندی بالکل دھوکہ ہے لیکن ہمارے مذہب نے اشد ضرورت کے وقت اس
بات کی اجازت دی ہے کہ چھوٹی عمر میں بھی لڑکی کی شادی کی جاسکتی ہے لیکن اس صورت
میں لڑکی کو اختیار ہوگا کہ وہ بڑی ہو کہ اگر اس شادی کو پسند نہیں کرتی تو مجسٹریٹ
لے حضور کے قضائی فیصلے رجسٹر نمبر ۲ ما دار القضاء ربوہ
۲۱۵
له المبسوط مي
Page 96
۹۳
کے پاس درخواست دے کر اس نکاح کو فسخ کرائے.عام طور پر باقی فقہائے اسلام ایک
بات کے قائل ہیں کہ ایسا نکاح اگر باپ نے پڑھوایا ہو تو نکاح فسخ نہیں ہو سکتا لیکن
ہماری جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ ہر صورت میں نکاح فسخ ہو سکتا ہے خواہ باپ نے کرایا
گئی
ہو یا کسی اور نے کیونکہ جب لڑکی کی رائے بلوغت میں باپ کی رائے پر مقدم سمجھی
ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ باپ کے پڑھوائے ہوئے نکاح کے بعد جب لڑکی بالغ ہو تو اس
حق رضامندی کو اسے واپس نہ دیا جائے" سے
ه
خیار بلوغ او قاضی کا فیصلہ
خیار بلوغ کے سلسلہ میں یہ سوال بڑا اہم ہے کہ نابالغ کے بالغ ہونے کے بعد خیار بلوغ کا
حق استعمال کرنے کے ساتھ ہی نکاح فسخ ہو جاتا ہے یا عدالت کے باضابطہ فیصلہ کے ساتھ فسخ ہوتا
ہے.جمہور فقہاء کے نزدیک خیار بلوغ کا حق استعمال کر لینے سے نکاح
خود بخو د فسخ نہیں ہوتا بلکہ
اس وقت تک قائم رہتا ہے جب تک کہ عدالت اس کے فسخ کا حکم جاری نہ کر دے.امام سرخسی
اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں :-
" فقہاء نے خیار بلوغ میں فسخ نکاح کے لئے عدالت کے حکم کی جو شرط لگائی ہے
اس کی وجہ یہ ہے کہ لڑکی کا بلوغ کے بعد نکاح کو رد کر دینا شوہر کے کئی نقصانات کا
موجب بنتا ہے اور یہ امر قرین انصاف نہیں کہ ایک معاہدہ جو صحیح طور پر منعقد ہوا
ہو اور اپنے اثرات و نتائج کے اعتبار سے نافذ بھی ہو محض ایک فریق کے رد کر دینے
له الفضل ۲۲ اکتوبر ۶۱۹۲۹
Page 97
۹۴
سے دوسرے فریق کے نقصان اُٹھانے کا مستوجب قرار پائے.اس لئے ضرورت ہے
کہ کوئی تیسرا شخص عورت اور مرد دونوں کے بیان لے اور اس امر کا جائزہ لے کہ خیار
بلوغ کا حق صحیح طور پر اور صحیح وقت پر استعمال کیا گیا ہے یا نہیں.نیز یہ کہ آیا فریق
متعلقہ سے کوئی ایسا فعل تو سرزد نہیں ہوا جس سے یہ ثابت ہو کہ بلوغ کے بعد لڑکی تھے
اس نکاح کو تسلیم کر لیا تھا یا اپنے اس حق سے وہ دستبردار ہوگئی تھی ظاہر ہے کہ ان
امور کا فیصلہ عدالت کر سکتی ہے کیونکہ عدالت ایک غیر جانبدارا دارہ ہے اور اس امر
کی ازروئے قانون مجاز ہے کہ وہ حالات پیش آمدہ کا جائزہ لینے کے بعد اپنے فیصلہ
سے کوئی ضررہ کسی دوسرے شخص کے ذمہ لازم کر دے" سے
دفعہ نمبر ۴۱
خیار بلوغ کے حق کا استعمال بلوغت کے بعد معقول مدت کے اند ر جلد
ہونا لازمی ہے.تشریح : « بعض فقہاء نے خیار بلوغ کے استعمال کی مدت میں بڑی سختی سے کام لیا ہے
اُن کے نزدیک اگر کوئی نابالغ لڑکی اپنے ولی کے کرائے ہوئے نکاح کو نا پسند کرتی
ہے تو اسے چاہیئے کہ بالغ ہونے کے فوراً بعد خیار بلوغ کا حق استعمال کرے یا اگر
نکاح کا علم نہیں تھا تو بالغ ہونے اور نکاح کا علم ہونے کے فوراً بعد اِس حق کو
استعمال کرسے " سے
فقہ احمدیہ خیار بلوغ کے حق کو استعمال کرنے کی مدت کو اہمیت نہیں دیتی.چونکہ اصولی طور پر بالغ
له المبسوط كتاب النكاح باب نكاح الصغير والصغيرة
له المبسوط م
۲۱۵
Page 98
۹۵
ہونے کے بعد اپنا نکاح کہہ کرنے کا حق مسلم ہے اس لئے اس حق کو اولیت حاصل ہوگی اور مدت کا
معاملہ ثانوی امر ہو گا جس کا فیصلہ تنازعہ زیر غور کے مخصوص حالات کے پیش نظر کیا جائے گا حضت
ا
خلیفہ المسیح الثانی فرماتے ہیں :-
یہ محض عقلی چیز ہے.عقلاً کسی لڑکی کے متعلق جتنا عرصہ ضروری سمجھا جائے گا اسکے
لئے ہم خیار بلوغ کی وہی معیار قرار دیں گے.اس میں سالوں یا عمر کی تعین نہیں کی
جاسکتی خیار بلوغ کی تشریح آخر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں فرمائی گذشتہ
فقہاء نے کی ہے اور چونکہ یہ تشریح فقہاء نے کی ہے اس لئے ہر زمانہ کے فقہاء کو اختیار
ہے کہ وہ اِس بارہ میں عقلی طور پر جو فیصلہ مناسب سمجھیں کریں.ایک وقت ایسا تھا
جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اردگرد صحابہ" کی تمام جماعت رہتی تھی اور فتونی
جماعت کے تمام افراد میں اُسی وقت پھیل جاتا تھا لیکن اب وہ زمانہ ہے کہ لوگ دینی
مسائل سے اکثر نا واقف ہوتے ہیں اس نا واقفیت کی بناء پر جتنی دیر ضروری سمجھی
جائے گی اس کو ملحوظ رکھنا پڑے گا کیونکہ دینی مسائل سے نا واقفیت خود اپنی ذات
میں ایک ایسی چیز ہے جو فتویٰ کو بدل دیتی ہے " سے
ایک اور قضائی فیصلہ میں حضور فرماتے ہیں :-
" اظہار نفرت نکاح کے بعد معقول طور پر قریب عرصہ میں ثابت ہے اور سوال
صرف بہت قریب کا ہے تو میرے نزدیک ایسے مشکوک فرق کے لئے ہم عورت کے حق
کو باطل نہیں کر سکتے خصوصا جب کہ ہم دیکھتے کہ خیار بلوغ کا مسئلہ ایسا مسئلہ نہیں
ہے جس سے عام طور پر لوگ واقف اور آگاہ ہوں ایسے مسائل کے متعلق قدرتی طور
پر تر دو زیادہ ہوتا ہے یا کے
له الفضل ۳۱ اکتوبر ۶۱۹۴۴
کے حضور کے قضائی فیصلہ جات کا رجسٹر نمبر ۲ ص دارالقضاء ربوہ
Page 99
94
دفعہ نمبر ۴۲
فسخ نکاح
عورت یا مرد کے مطالبہ پر مندرجہ ذیل وجوہات میں سے کسی ایک یا زائد وجوہ
کی بناء پر قاضی میاں بیوی میں علیحدگی کا فیصلہ کر سکتا ہے.اس طرز کی علیحدگی
کو فقہ کی اصطلاح میں فسخ کہتے ہیں.وجوہات فسخ گیارہ ہیں :-
ا - خاوند مفقود الخبر ہو.۲.خاوند غیر معمولی لمبے عرصہ کے لئے قید ہو.۳.خاوند نامرد ہو.- خاوند کسی متعدی بیماری میں مبتلا ہو.۵ - خاوند دائم المریض ہو.A
- خاوند نان و نفقہ دینے کا اہل نہ ہو یا قضائی فیصلہ کے با وجو د نان و نفقہ ادا کرنے سے عملاً افکاری
ہو.ے.عورت اپنے حق بلوغ کو استعمال کرے..خاوند ایلاء یا ظہار کرے اور چار ماہ کی مدت کے اندر اپنی قسم سے رجوع نہ کرے.۹ - نکاح فاسد ہو اور وجہ فساد دور نہ ہوئی ہو خواہ کوئی فریق اس بناء پر علیحدگی کیلئے رضامند
ہو یا نہ ہو.-۱۰- خاوند اور بیوی میں لعان ہو.
Page 100
94
11 - عورت دائم المریض ہو یا کسی اور وجہ سے وظیفہ زوجیت ادا کرنے کی اہل نہ ہو اور یہ ثابت ہو
کہ یہ عیوب اس میں نکاح سے قبل پائے جاتے تھے.تشریح :- فسخ اور طلاق میں فرق یہ ہے کہ طلاق خاوند کی طرف سے دی جاتی ہے اس صورت میں
مهر بالعموم خاوند کے ذمہ واجب الا وا ہوتا ہے اور اس کی عدت تین حیض با تین ماہ یا وضع حمل ہوتی
ہے لیے لیکن فسخ کا تعلق خاوند کے ساتھ نہیں ہوتا بلکہ قاضی بیوی یا میاں یا کسی اور کی درخواست پر علیحدگی
کا فیصلہ دیتا ہے اور اس کی عدت صرف ایک حیض یا ایک ماہ یا وضع حمل ہوتی ہے.فسخ کی بعض صورتوں میں عورت علیحدگی بھی حاصل کرتی ہے اور مہر کی حقدار بھی ہوتی ہے اور بعض
صورتوں میں خاوند مہر ادا کرنے کا ذمہ دار نہیں ہوتا مثلاً بیوی میں بعض ایسے جسمانی عوارض ہوں جو
وظیفہ زوجیت کی ادائیگی میں مانع ہوں مثلاً رتق وغیرہ کی وجہ سے اگر نکاح فسخ ہو تو مردمہر ادا کرنے کا
ذمہ دار نہ ہوگا.اگر علیحدگی میں عورت کا کوئی قصور نہ ہو بلکہ مرد کے کسی جسمانی عیب یا نقص کی وجہ سے
فسخ نکاح ہوا ہو تو مردمہر ادا کرنے کا ذمہ دار ہوگا.فسخ نکاح کی صورت میں علیحد گی طلاق بائن کے حکم میں ہوتی ہے سوائے لعان کے کیونکہ اس
صورت میں علیحد گی ایسی دائمی طلاق کے حکم میں ہوتی ہے جس کے بعد کسی صورت میں بھی دوبارہ نکاح
مذکورہ بالا وجوہات فسنح میں سے بعض کی تشریحات درج ذیل ہیں :-
بجائز نہیں ہوتا.ا مفقود الخبر
اس سلسلہ میں دو امور پر بحث کی جاتی ہے :-
ا - مفقود الخبر کے ورثے کی تقسیم -
ب - مفقود الخبر کی زوجہ کا کسی دوسرے شخص سے نکاح کرنا.زیر بحث دفعہ میں اس وقت شق "ب " مد نظر ہے مفقود الخبر ہونے کی بناء پر فسخ نکاح کیلئے
کیسی مدت کی تعیین کی کوئی نص موجود نہیں یہی وجہ ہے کہ فقہاء نے زمانہ کے حالات کے مطابق اندازے
لے دیکھیں واقعہ نمبر ۴۳
Page 101
۹۸
سے مختلف ہدتیں مقرر کی ہیں اور اس بارے میں تفاوت یہاں تک پایا جاتا ہے کہ جہاں بعض فقہاء
نے ایک سال کی مدت مقرر کی ہے وہاں بعض دوسرے فقہاء اس عرصہ انتظار کو تو نے سال تک
لے گئے ہیں لیے
موجودہ ترقی یافتہ ذرائع مواصلات کے پیش نظر فقہ احمدیہ کے مطابق خاوند کے مفقود الخبر
ہونے کی بناء پر علیحدگی کے لئے کوئی خاص مدت مقرر کرنا ضروری نہیں تاہم احتیاط کے تقاضہ
کے پیش نظر عدالت کی طرف سے کم از کم دو سال کی مدت مقرر کر دی جائے تو مناسب ہوگا.بهر حال مناسب یہ ہے کہ آخری فیصلہ قاضی یا عدالت مجاز کے اختیار میں ہو.حالات کے.مطابق جتنا وصہ وہ مناسب خیال کرے اتنا عرصہ انتظار کے بعد مفقود الخبر کا نکاح منسوخ کر کے
دوسری جگہ نکاح کرنے کی اجازت دے دے.۲.ایلاء اور ظہار
:- ایلاء یہ ہے کہ خاوند قسم کھائے کہ وہ عورت سے ازدواجی تعلقات قائم نہیں کرے گا.اس
صورت میں مرد کو چار ماہ تک مہلت دی جائے گی کہ اس مدت کے دوران وہ اپنی قسم توڑ کر بیوی
کے حقوق زوجیت ادا کرے ورنہ بیوی کو اختیار ہو گا کہ چار ماہ کی مدت گزرنے پر بذریعہ عدالت
فسخ نکاح کا مطالبہ کر ہے.ب : ظہار یہ ہے کہ مرد اپنی بیوی کو اپنی ماں کی طرح قرار دئے.عرب اس کے لئے یہ محاورہ
استعمال کرتے تھے " انتِ عَلَى ظَهْرِ اُمی ایسی صورت میں بھی خاوند کو مجبور کیا جائے گا کہ
وہ چار ماہ مدت کے اندر اپنی اس قسم کا کفارہ ہے ادا کر کے بیوی کے حقوق ادا کرے ورنہ چار ماہ کی
له الاسرة في الشرع الاسلامي باب المفقوده مطبوعه بيروت ۱۹ مولفه عمر فروخ -
جامع الضروريات لانواع المعاملات من مولفه محمد عبد الباقى الافغاني
ت قسم توڑنے کا کفارہ دس مساکین کوکھانا کھلانا یا لباس پہنانا ہے اور اگر یہ نہ کرسکے تو تین روزے رکھنا ہے
ایلاء کا ذکر قرآن کریم کی سورۃ البقرہ آیت نمبر ۲۲۷ میں ہے.ے ظہار اور کفارہ کا ذکر قرآن کریم ک سورہ مجادلہ آیت سوتاہ میں ہے اور اس
کا کفارہ یہ ہے کہ تعلق زوجیت قائم
کرنے سے پہلے خاوند مسلسل دو ماہ کے روزے رکھے اور اگریہ نہ کر سکے تو ساٹھ مساکین کو کھانا کھلائے.
Page 102
99
مدت گذرنے پر عورت کو اختیار ہو گا کہ وہ بذریعہ عدالت فسخ نکاح کا مطالبہ کرے.مریضہ بیوی
بعض اوقات عورت میں کوئی ایسا عیب ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ وظیفہ زوجیت کے ادا کرنے کی
اہل نہیں ہوتی مثلاً وہ آتشک یا جذام کی مریضہ ہے، مہلک تپ دق میں مبتلا ہے اس میں قرن یا رتی کا
عیب ہے اور نکاح کے وقت مرد کو عورت کے ان عیوب
کا علم نہیں ہو سکا اس کا علم اسے شادی کے
بعد ہوا اس صورت میں خاوند قاضی کے سامنے صورتِ حال بیان کر کے فسخ نکاح کا مطالبہ کو سکتا ہے.بے شک خاوند اپنی ایسی بیوی کو طلاق بھی دے سکتا ہے لیکن اس صورت میں اسے مہر ادا کرنا
پڑے گا لیکن اگر وہ اس عذر کی بناء پر قاضی کے ذریعہ نکاح فسخ کر ائے تو اسے مرادانہیں کرنا پڑے گا.دفعہ نمبر ۴۳
نکاح صحیح ہو یا فاسد جب وہ خلوت صحیحہ کے بعد کسی وجہ سے ختم ہو
یا خاوند کی وفات ہو جائے تو اس طرح نکاح کے ختم ہونے کے بعد عورات
ایک مدت معینہ گزارتی ہے اور اس عرصہ کو عدت کہتے ہیں.قرین : عورت کی شرمگاہ میں سینگ کی طرز کی اُبھری ہوئی ہڈی کا ہونا جس کی وجہ سے وہ
جماع کے ناقابل ہوتی ہے.رتو : شرمگاہ کے اندرونی حصہ کا مضبوط جھلی کی وجہ سے بند ہو جانا.اس وجہ سے بھی وہ جماع
کے قابل نہیں رہتی.
Page 103
تشریح : اللہ تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے :-
النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَاحْصُوا الْعِدَّةَ
وَاتَّقُوا اللهَ رَبِّكُمْ.له
یعنی اے نبی اور اس کے مانے والوجب تم بیویوں کو طلاق دو تو ان کو مقررہ وقت کے
مطابق طلاق دو اور طلاق کے بعد وقت عزت کا اندازہ رکھو اور اللہ کا جو تمہارارت
ہے تقوی اختیار کرو.اسی طرح ایک اور جگہ عدت کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا :-
وَالْمُطَلَّقْتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُوءٍ له
یعنی جن عورتوں کو طلاق مل جائے وہ تین بار حیض آنے تک اپنے آپ کو روکے رکھیں.عدت کے دوران نکاح کا معاملہ نہ کرنے کا حکم اس آیت سے بھی ثابت ہے :-
وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَبُ أَجَلَهُ - س
یعنی جب تک عدت
کا حکم اپنی میعاد کو نہ پہنچ جائے اس وقت تک تم نکاح باندھنے کا
پختہ ارادہ نہ کرو.: نکاح کے بعد اور خلوت صحیحہ سے پہلے اگر میاں بیوی میں طلاق ، خلع یا فسخ کے ذریعہ جدائی ہو
گئی ہو تو عورت پر کوئی عدت نہیں.وہ جدائی کے بعد کسی وقت بھی دوسرے مرد سے نکاح کر سکتی ہے.اللہ تعالیٰ قرآن
کریم میں فرماتا ہے :.إذا نعم المُؤْمِتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَالَكُمْ
نَكَعْتُمُ
عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّ ونَهَا - له
یعنی جب تم مومن عورتوں سے شادی کرو پھر ان کے چھونے سے پہلے طلاق دے دو تو تم کو
کوئی حق نہیں کہ ان سے عدت کا مطالبہ کرو.ب :.نکاح صحیح ہو یا فاسد اگر اس کے بعد خلوت صحیحہ میسر آجائے اور پھر کسی وجہ سے بھدائی
نے سورة الطلاق آیت ۲
سے سورۃ البقرہ آیت ۲۳۶
سورة البقره آیت ۲۲۹
سے سورۃ الاحزاب آیت ۵۰
Page 104
ہو تو عورت کے لئے عدت ضروری ہے لیے
ج - اگر جدائی طلاق کے ذریعہ ہو تو عدت تین حیض ہے لیے
د - اگر کیسی عورت کو حیض نہیں آتا تو اس کی عدت تین قمری مہینے ہے.خدا تعالیٰ فرماتا ہے.وَإِلَى يَسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ اِنِ التَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَثَةَ أَشْهُرٍ
والي لَمْ يَحِضْنَ سے
یعنی تمہاری بیویوں میں سے وہ عورتیں جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں اگر اُن کی عدت
کے متعلق تمہیں شبہ ہو تو ان کی عدت تین مہینے ہے اور اسی طرح ان کی بھی جن کو
حیض نہیں آرہا.هـ - اگر عورت حاملہ ہے تو اس کی عدت وضع حمل یعنی ولادت ہے.اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں
فرماتا ہے :-
و أولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ له
یعنی جن عورتوں کو حمل ہو ان کی عدت وضع حمل تک ہے.سُئِل سُبَيْعَةُ الأَسْلَمِيَّةُ كَيْفَ افْتَاهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقَالَتْ أَفْتَانِى إِذَا وَضَعَتِ أَنْ أَنْكِحَه
یعنی سبیعہ اسلمی جو عدت وفات گزار رہی تھی اور حاملہ تھی اس سے پوچھا گیا کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے عدت کے بارہ میں انہیں کیا ارشاد فرمایا تو انہوں نے جواب دیا
کہ آپ نے فرمایا جب بچہ پیدا ہو جائے تو تم نکاح کر سکتی ہو.امام شعرانی لکھتے ہیں :-
اتَّفَقَ الأَئِمَّةُ عَلَى انَّ عِدَّةَ الْعَامِلِ مُطلَقًا بِالْوَضع سَوَادُ الْمُتَوَلَّى
عَنْهَا زَوْجُهَا وَالْمُطَلَّقَةٌ لَه
لے سورۃ البقرہ آیت ۲۳۶
له سورة البقره آیت ۲۲۹
۲۱۳ سورة الطلاق آیت ۵
نے مسلم کتاب الطلاق باب القضاء عدة المتوفى عنها زوجها -
ن الميزان الكبرى للشعراني مص مصرى -
Page 105
۱۰۲
یعنی اللہ مذاہب اس بات پر متفق ہیں کہ حاملہ کی ہر
قسم کی عدت وضع حمل ہے.و اگر جدائی خلع یا نسیخ نکاح کی صورت میں ہو تو عدت ایک حیض ہے اور اگر حیض نہیں آتا تو
عدت ایک ماہ ہے اور اگر حاملہ ہے تو عدت وضع حمل ہے.حدیث کے الفاظ یہ ہیں :-
عَنِ الرَّبيع بنت معوذ بن عفراءَ أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ تَعْتَدَ
بحيضة.یعنی ربیعہ بنت معوذ کے متعلق روایت ہے کہ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
زمانہ میں اپنے خاوند سے خلع لیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ وہ ایک
حیض عدت گزاریں.ز - نکاح کے بعد اگر خاوند فوت ہو جائے تو عدت وفات چار ماہ دس دن ہے اور اگر عورت
حاملہ ہے تو اس کی عدت وضع حمل ہے.اللہ تعالیٰ قرآن
کریمہ میں فرماتا ہے :-
وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ
اشْهُرٍ وَعَشْرًا:
یعنی تم میں سے جن لوگوں کی روح قبض کر لی جاتی ہے اور وہ اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ
جاتے ہیں چاہیئے کہ وہ بیویاں اپنے آپ
کو چار مہینے اور دس دن تک روک رکھیں.اگر کوئی عورت عدت طلاق یا عدت فسخ گزار رہی ہو اور اس دوران میں اس کا خاوند فوت
ہو جائے تو اس عورت کی سابقہ عدت ساقط ہو جائے گی اس کی بجائے اس کے لئے " عدت وفات
گزارنا ضروری ہوگا اور وہ خاوند کی وراثت سے حصہ پائے گی.عدت کی خواہ کوئی صورت ہو اس کے دوران نکاح جائز نہیں.اگر کوئی شخص لاعلمی کی وجہ
سے عدت کے دوران نکاح کرے اور تعلقات زوجیت بھی قائم ہو جائیں تب بھی فریقین کے درمیان
تفریق لازم ہوگی البتہ عدت گزارنے کے بعد فریقین اگر چاہیں تو دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں.امام ابو حنیفہ اور امام شافعی" کا مذہب یہی ہے کہ عدت کے دوران نکاح ہو جانے سے
۱۴۲
ترمذی كتاب النكاح باب الخلع )
کے سورة البقرة : ۲۳۵
Page 106
۱۰۳
ابدی حرمت لازم نہیں آتی بلکہ تفریق کروا دینے اور عدت گزرنے کے بعد دوبارہ نکاح ہوسکتا ہے لیے
سوائے اس کے کہ مرد اور عورت نے عمدا اس طرح نکاح کیا ہو اور معاشرتی مصالح کا تقاضا ہو کہ
انہیں بطور سزا با ہمی نکاح کے حق سے محروم کر دیا جائے.جو نکاح دوران عدت کیا جائے وہ اپنے
اثرات کے اعتبار سے نکاح فاسد کے حکم میں ہے.اس بارہ میں ایک حدیث کے الفاظ یہ ہیں :-
رفع إلى عُمَرَ امْرَأَة تَزَوَّجَتْ فِي الْعِدَّةِ فَضَرَبَهَا وَضَرَبَ زَوْجَهَا
بِالمِخْفَقَةِ ضَرَبَاتٍ وَفَرَقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ قَالَ أَيُّهَا امْرَأَةِ نَكَحَتْ فِي
عِدَّتِهَا فَإِنْ كَانَ زَوْجُهَا الَّذِي تَزَوَجَهَا لَمْ يَدْخُلُ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا
وَاعْتَدَتْ بَقِيَّةَ عِدَّ تِهَا مِنَ الْاَوَّلِ ثُمَّ كَانَ الْأَخَرُ خَاطِيَّا مِنَ الْخَطَّابِ
وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَرقَ بَيْنَهُمَا ثَمَّ اعْتَدَّتْ بَقِيَّةُ عِدَّ تِهَا مِنَ الْاَوَّلِ
ثُمَّ اعْتَدَّتْ مِنَ الْأَخَرِثُمَّ لَا يَجْتَمِعَانِ اَبَدًا له
σ
یعنی ایک عورت نے عدت کے دوران نکاح
کر لیا.جب اس کی شکایت حضرت عمر کو ملی
تو انہوں نے مرد و عورت دونوں کو کوڑے لگوائے اور پھر فرمایا اگر تو اس نے مباشرت
نہیں کی تو ان میں تفریق کروا دی جائے اور پھر عدت کے بعد اگر یہ چاہیں تو نکاح کر سکتے
ہیں اور اگر انہوں نے مباشرت کر لی ہے تو پھر دائمی تفریق ہوگی دونوں عدتوں کے بعد
بھی یہ نکاح نہیں کر سکیں گے.ل بداية المجتهد ص
له.مؤطا امام مالك
۳۹
ه
Page 107
دفعہ نمبر ۴۴
نان و نفقه
خاوند اپنی بیوی کے نفقہ کا ذمہ دار ہے سوائے اس کے کہ بیوی خاوند
کی مرضی کے خلاف کسی شرعی عذر کے بغیر اس سے علیحدہ رہائش اختیار
کرے اور نشوز کی مرتکب ہو.تشریح
خاوند اپنی بیوی کے نان و نفقہ کا ذمہ دار ہے اور یہ ذمہ داری قرآن
کریم اور احادیث
سے ثابت ہے.اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے :-
الرِّجَالُ قَوْمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
انْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ له
یعنی مرد اس فضیلت کے سبب سے جو اللہ نے ان میں سے بعض کو دوسروں میر دی ہے
اور اس سبب سے کہ وہ اپنے مالوں میں سے عورتوں پر خرچ کرتے ہیں عورتوں پر نگران
قرار دئیے گئے ہیں.احادیث سے ثابت ہے کہ بیوی کے نان و نفقہ کے بارے میں خاوند کی ذمہ داری اس کی مالی
حیثیت کے مطابق ہے، تاہم نان و نفقہ کی یہ اصولی ذمہ داری خاوند کی مالی حیثیت سے قطع نظرقائم
رہتی ہے جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے :.وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقُ مِمَّا اللهُ اللهُ له
یعنی جو شخص تنگدست ہو تو اللہ تعالیٰ نے جتنا بھی اس کو دیا ہو وہ اس میں سے اپنی بیوی
ل سورة النساء : ۳۵
نے بخاری کتاب النفقات ما
سورة الطلاق : ٨
Page 108
۱۰۵
کو نفقہ دے.اگر کوئی شخص بیوی کے نان و نفقہ کی بالکل استطاعت نہیں رکھتا تو بیوی کے مطالبہ پر میاں بیوی
میں تفریق کروائی جاسکتی ہے.چنانچہ حدیث میں ہے:
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّجُلِ لَا يَجِدُ مَا
يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ قَالَ يُفْرَقُ بَيْنَهُمَا
حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک تنگ دست شخص جو اپنی زوجہ کو خرچ دینے کی
بالکل استطاعت نہیں رکھتا تھا اس کے بارہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اس کی بیوی کو حق علیحدگی حاصل ہے.خاوند پر بیوی کو نفقہ دینے کی ذمہ داری اصولی ہے بیوی کا صاحب جائیداد ہونا اس ضمن
میں غیر متعلق ہے کیونکہ خاوند اپنی صاحب جائیدا دبیوی کے نان و نفقہ کا بھی ذمہ دار ہے.نان ونفقہ
سے مراد زمانہ کے دستور اور معروف طریق کے مطابق خوراک، لباس اور رہائش مہیا کرنا اور علاج معالجہ
کے اخراجات برداشت کرنا ہے.بیوی اگر بلا عذر شرعی خاوند سے علیحدگی اختیار کئے رکھے یا نشو از اختیا ر کرے تو وہ نان و نفقہ کی
حقدار نہیں رہتی.عذر شرعی سے مراد ایسا عذر ہے جسے شریعیت تسلیم کرے مثلاً بیوی کا مہر معجل طلب کرنا اور خاوند
کا ادا نہ کرنا.ایسے ہی بیوی کی ایسی طبعی حالت جیسے حیض یا نفاس کے ایام ہیں جن کی وجہ سے وہ فرائض
زوجیت ادا کرنے کے قابل نہیں رہی.یہ سب امور خاوند سے علیحدگی اختیار کرنے کا شرعی عذر مہیا کرتے
ہیں.اسی طرح خاوند کے جبر و تشدد سے تنگ آکر مجبورا علیحدگی اختیار کرنا یا کسی ایسی جائزہ شرط کی بناء پر
علیحدگی اختیار کرنا جو بوقت نکاح طے ہو چکی ہو عذر شرعی کے ذیل میں آئے گا.پس اگر بیوی اس
قسم کے کسی عذر شرعی کی وجہ سے علیحدگی اختیار کرے تو وہ با وجود علیحدگی اختیار
کرنے کے نان و نفقہ کی حقدار ہو گی.لدار قطنی بحواله نيل الأوطار كتاب النفقات باب اثبات الفرقة للمرأة إذا تعذرت النفقة
جلد ۳۲۶
و بحواله فتح القدير من اس
کے نشوز کے مفہوم کے لئے دیکھیں باب الطلاق صاف
--
Page 109
1.4
دفعہ نمبر ۴۵
نان و نفقہ ادا کرنے کی ذمہ داری بصورت طلاق ایام عدت تک قائم رہتی ہے
اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے:
اسكنُوهُنَّ مِنْ حَيْتُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَ وهُنَّ لِتُفَيَقُوا
عليمن
یعنی مطلقہ عورتوں کے حق کو نہ بھولو ان کو وہیں رکھو جہاں تم اپنی طاقت کے مطابق
رہتے ہو اور ان کو کسی قسم کا ضرر نہ دو اس طرح کہ ان کو تنگ کر کے گھر سے نکال دو.تشریح چونکہ عدت کے دوران خاوند اور بیوی کا تعلق اس حد تک قائم رہتا ہے کہ خاوند
عدت کے دوران رجوع کر سکتا ہے اور اگر طلاق بائن ہے تو بھی عورت عدت کے دوران کسی دوسری
جگہ شادی نہیں کر سکتی اس لئے عدت کے عرصہ کے لئے خاوند پر بیوی کا نان و نفقہ واجب ہے اگرچہ
بعض روایات اس کے خلاف بھی ہیں مگر احسان کے نزدیک یہ امر مسلمہ ہے کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو طلاق
دے دے خواہ وہ رجعی ہو یا بائن مرد پر عدت کے دوران کا نان ونفقہ واجب ہے.اس بارہ میں صاحب فتح القدیر لکھتے ہیں :-
إذا طَلقَ الرّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلَهَا التَّفَقَةُ له
یعنی جب کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو وہ عدت کے دوران نفقہ لینے کی
حقدار ہے.عدت وفات کے ایام میں بیوہ کا نفقہ حتماً واجب نہیں کیونکہ مرنے والے کی اپنے مال پر ملکیت
ختم ہو جاتی ہے اور متوفی کا مال ترکہ کی صورت میں دیگر ورثاء کے پاس جا چکا ہوتا ہے اور بیو بھی
اپنے حصہ کے مطابق ترکہ کی وارث ہو چکی ہوتی ہے البتہ جیسا کہ دفعہ نمبر ۶ہ سے ظاہر ہے بطور حسن سلوک
ایک سال تک رہائش مہیا کرنے کی وصیت کرنا ضروری ہے.ے سورۃ الطلاق آیت
فتح القدير ص
۳۳۹
Page 110
دفعہ نمبر ۴۶
1.4
بیوہ عدت وفات اور اس کے بعد ایک سال تک اپنے مرحوم خاوند کے
مکان میں سکونت کا حق رکھتی ہے خواہ وہ مکان ترکہ میں کستی دیگر وارث کے حصہ
میں آیا ہو.اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے:
وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا هِ ۖ وَصِيَّةً لِازْوَجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى
الْحَوْلِ غَيْرَ اِخْرَاجِ ، فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ
مِن مَّعْرُونٍ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمه
یعنی تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں وہ اپنی بیویوں کے
حق میں ایک سال تک فائدہ پہنچانے یعنی ان کے گھروں سے نہ نکالنے کی وصیت کر جائیں
لیکن اگر وہ خود بخود چلی جائیں تو وہ اپنے متعلق جو پسندیدہ بات کریں اس کا تمہیں
کوئی گناہ نہیں اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے.سید نا حضرت مصلح موعود اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں :-
" بعض نے کہا ہے کہ یہ آیت احکام میراث کے ذریعہ منسوخ ہو گئی ہے مگر یہ بالکل غلط
ہے.بیوہ کا اپنے خاوند کی جائیداد میں جو حصہ رکھا گیا ہے اس کے ساتھ اس کا کوئی
تعلق نہیں یہ ایک الگ حکم ہے جس میں جائیداد کے حصہ کے علاوہ عورت کے لئے سال بھر کے
نان
و نفقہ اور رہائش کا انتظام ضروری قرار دیا گیا ہے....یہ ان سے نیک سلوک
کرنے کا ایک زائد حکم دیا گیا ہے.“ کے
علامہ حقاص اپنی مشہور کتاب احکام القرآن میں بیوہ کے نفقہ پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں :-
روَى الشَّعْبِيُّ عَنْ عَلَى وَعَبْدِ اللهِ قَالَا إِذَا مَاتَ عَنْهَا زَوْجَهَا فَتَفْقَتُهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ له
یعنی حضرت علی اور عبد اللہ بن عباس دونوں نے کہا ہے بیوہ کا نفقہ (بطور احسان)
کل ترکہ سے ادا ہو گا.ل سورة البقره آیت ۲۴۱
۴۹۸
س تفسير كبير سورة البقرة من ۵۲
کے احکام القرآن للجصاص خدا نیز دیکھیں قرطبی ص ۲۳ مطبوعہ مصر ۶۱۹۶۶
Page 111
1.A
دفعہ نمبر ۴۷
باپ اپنی نابالغ اولاد کے نفقہ کا حسب استطاعت ذمہ دار ہے.تشریح
بچہ کے نان و نفقہ کی قانونی ذمہ داری باپ پر اسی صورت میں ہے جبکہ بچہ خود صاحب
جائیداد نہ ہو.اگر بچے کے پاس وافر جائیداد ہو اور اس سے اس کے اخراجات باستانی ادا ہو سکتے
ہوں تو باپ اپنے پاس سے یہ اخراجات ادا کرنے کا قانونا ذمہ دار نہ ہوگا.دفعہ نمبر ۴۸
ه
ماں باپ
کا نفقہ
ماں یا باپ اگر ضرورت مند ہوں اور ان کی اپنی کوئی ایسی جائیداد نہ
ہو جو ان کی کفالت کر سکے تو حسب حالات اور استطاعت بیٹا ان کے
نان و نفقہ کا ذمہ دار ہے.تشریح اللہ تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے :-
ہے.ووصينا الإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ احْسُنَاط
یعنی اپنے والدین سے حسن سلوک کرنا اور ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنا اولاد کی ذمہ داری
له سورة الاحقاف آیت ۱۶
Page 112
1.9
حضانت
بچوں کی نگہداشت و پرورش عائلی زندگی کا اہم حصہ ہے یہ عام حالات میں ماں اور باپ
دونوں مشترکہ طور پر بچے کی نگہداشت کے ذمہ دار ہوتے ہیں لیکن اگر بد قسمتی سے دونوں میں اختلاف
پیدا ہو جائے اور نوبت طلاق، خلع یا علیحدگی تک پہنچے تو ایسی صورت میں کمسن بچوں کی پرورش ایک
معاشرتی مسئلہ بن جاتا ہے.شریعت نے ایسی صورت حال کے لئے بھی رہنما اصول مقر رکئے ہیں جن کی
روشنی میں یہ طے کیا جائے گا کہ بچہ ماں کے سپرد ہو یا باپ کے پاس رہے یا دیگر عزیز و اقارب کے پاس
اور یہ بھی رہنمائی فرمائی کہ یہ حق کی رشتہ داروں کو کن پابندیوں کے ساتھ کس ترتیب سے اور کس حد تک
حاصل ہو گا ان سب باتوں کی تفصیل آئندہ دفعات میں بیان ہوگی.دفعہ نمبر ۴۹
حضانت کی تعریف
بچے کے سن تمیز کو پہنچنے تک اس کی پرورش ، نگہداشت اور اس کو اپنے
پاس رکھنے کا حق حق حضانت کہلاتا ہے.تشریح
حضانت کا حق بچے کے سن تمیز کو پہنچنے تک کے عرصہ کے لئے ایک عارضی حق ہے اور یہ والد
کے حق ولایت سے مختلف نوعیت رکھتا ہے جیسا کہ آئندہ دفعات سے ظاہر ہوگا یہ کسی طرح بھی والد کے
حقیق ولایت سے متصادم یا اس سے بالا نہیں اور نہ ہی حضانت کسی اور کے پاس ہونے سے والد اپنی زیرہ ایویں
Page 113
11.سے آزاد ہو سکتا ہے.حضانت کا حق در اصل بچے کی بہبود کے پیش نظر نیز والدین کے جذباتی اور طبعی
میلانات کو مد نظر رکھ کر قائم کیا گیا ہے اور یہ حق بچے کی رضاعت ، جذباتی آسودگی ، متوازن نشو و نما
اور اخلاقی و جسمانی تربیت کے تقاضوں کے مطابق قائم یا ساقط ہوتا ہے.دفعہ نمبر ۵۰
ه
مدت حضانت
بیر خواہ لڑکا ہو یا لڑ کی اس کی حضانت کا حق اس
کی عمر توسال ہو جانے
رہے گا سوائے اس کے کہ یہ حق کسی وجہ سے اس سے قبل ساقط
کے کہ یہ
تک قائم رہے گا.ہو جائے.تشریح بعض فقہاء کے نزدیک لڑکے کے لئے حضانت کی عمر سات سال تک اور عض کے نزدیک
دو سال تک ہے.اسی طرح لڑکی کے لئے بعض فقہاء کے نزدیک عمر حضانت سات سال تک اور بعض
کے نزدیک سن بلوغت تک ہے مگر فقہ احمدیہ کے مطابق ہر دو صورتوں میں یہ حق نو سال کی عمر تک
قائم رہے گا اس کے بعد یہ حق ختم ہو جائے گا اور بچہ باپ کو لوٹا دیا جائے گا.در اصل شیر خوارگی اور اس کے معا بعد کے دور میں بچے کی دیکھ بھال اور اس کی کمزور طبعی
حالت کے پیش نظر بچے کی نشو و نما کے لئے ماں ایک طبعی اور فطری مناسبت رکھتی ہے اور اس
دور میں ماں کی گود بچے کی جذباتی آسودگی، صحت اور متوازن نشو و نما کے لئے ضروری ہوتی ہے اسلئے
اس دور میں بچہ کی بہبود کے پیش نظر ماں کے حق کو فائق تسلیم کیا گیا ہے مگر لڑکپن اور سن تمیز کو پہنچنے
کے بعد بچے کی ذہنی ، اخلاقی اور جسمانی تربیت کے تقاضے بدل جاتے ہیں جو باپ کی کفالت کے متقاضی
ہیں اس لئے بچے کا باپ کو لوٹا دیا جانا ہی احسن ہے.
Page 114
دفعہ نمبر ۵
استحقاق حضانت
1 - حضانت کا حق والدین باہمی رضامندی سے متعین کر سکتے ہیں اور یہی طریق
اولیٰ ہے.ب.اگر حضانت شق کر کے تحت طے نہ ہو سکے تو پھر یہ حق ثالث یا قاضی منذ جبریل
اصول کو سامنے رکھ کر متعین کرے گا.بشرط نبودی نابالغ.ماں حضانت کی
اولین حقدار ہے.ماں کے بعد علی الترتیب، نانی، دادی، پڑنانی ، پڑوادی،
بہن اور خالہ حضانت کی حقدار ہیں.اگر ان میں سے کوئی موجود نہ ہو تو حق
حضانت باپ اور باپ کی جانب سے دوسرے رشتہ داروں کو الاقرب
فالا قرب کے اصول پر طے ہو گا.تشریح
اگرچہ ماں کو حضانت کا اولین حقدار قرار دیا گیا ہے مگر یہ حق بچے کی بہبود کے تابع ہے
اگر ماں اور دوسرے دعویدار ان حضانت بچے کی بہبود کے لحاظ سے برابر ہوئی تو پھر ماں ہی اولین حقدار
ہے لیکن اگر بچے کا ماں کے پاس رہنا کیسی وجہ سے اس کی بہبود کے خلاف ہو تو ماں کو یہ حق نہیں دیا
جائے گا بلکہ متذکرہ ترتیب کے مطابق کیسی اور کو دے دیا جائے گا.
Page 115
۱۱۲
دفعہ نمبر ۵۲
اہمیت حضانت
حضانت کا اہل ہونے کے لئے لازمی ہے کہ حاضنہ یعنی جو حق حضانت
حاصل کرنے کی دعویدار ہے وہ بچے کی نگہداشت کر سکتی ہو مریض نہ ہوا
ناشتہ نہ ہو.تشریح
لبعض حالات میں ماں کے بعد بہن یا خالہ وغیرہ بچے کی حضانت کی دعویدار ہوسکتی ہیں
ایسی صورت میں بہن یا خالہ کا خود عاقلہ بالغہ اور بچے کی نگہداشت کے قابل ہونا ضروری ہے.اسی طرح حاضنہ اگر دائمی مریضہ ہو یا مجنون اور فائر العقل ہو تو وہ بھی محض آو پر دی گئی ترتیب میں
قرابت کی وجہ سے حضانت کی حقدار نہیں ہو جائے گی.دفعہ نمبر ۵
مناتے دوران نان نفقه
بچے کی حضانت خواہ کسی کے پاس ہو عرصہ حضانت کے دوران
بچے کا نان نفقہ
تشریح
باپ کے ذمہ ہو گا.بچہ کا نان ونفقه بوجه ولایت ذمہ داری اور ثبوت نسل باپ کے ذترہ ہوتا ہے اور اس کی
پر ذمہ داری عمومی ہے.باپ کے علاوہ کسی دوسرے کی نگرانی میں رہنے کی وجہ سے یہ ذمہ داری ختم نہیں
Page 116
ہوتی جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْتُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُونِ کہ جس کا
بچہ ہے وہ بچہ کی پرورش کے اخراجات ادا کرنے کا ذمہ دار ہے.حدو
حمد و د حضانر
دفعہ نمبر ۴ ۵
حضانت کا حق باپ کے حق ولایت کے تابع ہے.تشریح
بچے کا قانونی اور شرعی ولی اس کا باپ ہے ماں بچے کی ولیتہ نہیں اِس لئے حضانت کے
دوران بھی بچے پر باپ کی ولایت کا حق قائم رہتا ہے اور حاضنہ خواہ ماں ہو یا کوئی اور بچے کی پرورش
اس
کی تعلیم، دینی تربیت اور اس کی نشست و برخواست کے سلسلہ میں باپ کی معروف ہدایات
کی پابند
ہوگی.دفعہ نمبر ۵۵
ه
سقوط حضانت
حق حضانت حاصل ہو جانے کے بعد حاضنہ کے حالات کی تبدیلی سے یہ
ے سورۃ البقرہ آیت ۲۳۴
Page 117
۱۱۴
حق ساقط ہو سکتا ہے ایسی صورت میں حق حضانت از سیر کو متعین کیا جائیگا.تشریح جیساکہ بیان ہو چکا ہے حق حضانت ایک عارضی حق ہے اور محض بچے کی بہبود اور بھلائی
کے پیش نظر متعین کیا جاتا ہے اگر حضانت حاصل ہونے کے بعد کسی وقت بچے کی بہبودی متأثر
ہوتی ہے تو حق حضانت ساقط ہو جاتا ہے.مثلاً ماں اگر دوسری جگہ شادی کرلے تو اس کا حق حضانت
"
متاثر ہوگا.بعض فقہاء کے نز دیک اگر ماں نے بچے کے ذی محرم رشتہ دار سے شادی کی ہے تو حق حضانت
قائم رہے گا اور اگر بچہ کے غیر محرم سے شادی کی ہو تو حق حضانت ساقط ہو جائے گا.بعض فقہاء کے نزدیک دوسری شادی سے حق حضانت صرف اسی صورت میں ساقط ہوتا ہے
جب دوسرا خاوند خواہ محرم ہو یا غیرمحرم بچے کی ذمہ داری قبول کرنے کو تیار نہ ہو یا وہ بچہ کا خیر خواہ نہ ہو
ایک حدیث سے اس موقف کی تائید ہوتی ہے.ایک موقع پر حاضنہ جو کہ بچے کی خالہ تھی اس نے بچے کے
غیر محرم سے شادی کی ہوئی تھی مگر اس کے باوجود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضانت کا حق اس کی
خالہ کو ہی دلایا کیونکہ اس کا خاوند بچہ کی پرورش کی ذمہ داری لینے پر تیار تھا بلکہ وہ یہ حق حاصل کرنے کا
مطالبہ کر رہا تھا تے
بهر حال ائمہ فقہ کا اختلاف ظاہر کرتا ہے کہ اصل معیار بچے کی بہبود ہے.اگر ماں کی دوسری
شادی سے بچہ کی بہبود متاثر نہ ہوتی ہو اور سوتیلا باپ بچے کی ذمہ داری قبول کرنے کو تیار ہو تو یہ
حق ساقط نہیں ہوگا.فقہ احمدیہ بھی اِسی مسلک کو درست مانتی ہے اور قرار دیتی ہے کہ ماں کی دوسری شادی حق
حضانت پر از سر نو غور کرنے کی وجہ تو بن سکتی ہے محض شادی سے حق حضانت ساقط نہیں ہو سکتا خواہ
بچہ کا یہ سوتیلا باپ اس کا محرم ہو یا غیر محرم -
نیل الاوطار باب من احق بكفالة الطفل مس
Page 118
۱۱۵
نمبر ۵۶
خیارالیم
خيار التميز
بار
۱ - سن تمیز کو پہنچنے کے بعد بچے کی اپنی مرضی کا استعمال خيار التمییز کہلاتا ہے.ب بچے کا حق خیار التمیز بذریعہ قضاء نافذ ہوگا اور ہر صورت میں بچے کی بہبود
کے تابع ہوگا.ج - ایسی صورت میں نان و نفقہ کی ذمہ داری کی تعیین قضاء کرے گی.تشریح
بچے کی عمر نو سال ہو جانے پر حق حضانت ختم ہو جائے گا اور بچہ باپ کو لوٹا دیا جائے گا.البتہ اگر بچے کا مفاد تقاضا کرے اور بچے کی اپنی مرضی بھی حاضنہ کے پاس رہنے کی ہو تو بچے کو یہ اختیار
دیا جا سکتا ہے کہ وہ جس کے پاس چاہے رہے البتہ بچے کا یہ اختیار قاضی کے فیصلہ کے تابع ہوگا
اگر بچہ غلط نگران کو منتخب کرے تو بچے کی بہبود کے پیش نظر قاضی اس میں تبدیلی کر سکتا ہے.ایک
ایسے ہی تنازعہ میں بچے نے باپ کے پاس رہنے کو ترجیح دی چھان بین پر معلوم ہوا کہ بچہ کھلنڈرا ہے
اور ماں تعلیم پر زور دیتی ہے جبکہ باپ کو اس کی پرواہ نہیں اور اس وجہ سے بچہ باپ کے پاس جانے
کو ترجیح دیتا ہے ایسی صورت میں قاضی نے بحیہ کو ماں کے حوالے کر دیائیے
۲.بچے کی عمر تمیز کو پہنچنے کے بعد جتنے معاملات بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے
خلفاء راشدین کے سامنے آئے اور جن کو تاریخ نے محفوظ رکھا ان سب میں ممیز بچے کو یہ اختیار دیا
گیا ہے کہ چاہے تو باپ کے پاس رہے چاہے تو ماں کے پاس.ایسے واقعات کی نشاندہی کرنے کے
بعد صاحب نیل الاوطار لکھتے ہیں :.الظَّاهِرُ مِنْ اَحَادِيثِ الْبَابِ اَنَّ التَّخَيرَ فِي حَقٌّ مَنْ بَلَغَ مِنَ الْأَوْلَادِ
له نيل الأوطار باب من احق بكفالة الطفل جلده
۳۳۲
Page 119
إلى من التمييز هُوَ الْوَاجِبُ مِنْ غَيْرِ فَرْق بين الذكر والأنثى له
یعنی حضانت سے متعلق جو احادیث مروی ہیں اُن سے ظاہر ہوتا ہے کہ سن تمیز کو پہنچنے
والے بچے کو ماں باپ میں سے اپنا نگران منتخب کرنے کا اختیار دینا واجب ہے خواہ
بچہ لڑکا ہو یا لڑکی.ایک اور جگہ وہ لکھتے ہیں :.قِيلَ أَنَّ التَّنْبِيرَ أولى لِاِتِّفَاقِ الْفَاظِ الْأَحَادِيثِ عَلَيْهِ وَعَمَلِ الْخُلَفَاءِ
الراشدين له
یعنی ممیز بچہ کو انتخاب کا اختیار دینا زیادہ مناسب اور اولیٰ ہے کیونکہ احادیث کے
الفاظ اور خلفاء راشدین کا عمل اس پر متفق ہیں.له له نيل الأوطار باب من احق بكفالة الطفل جلد ٦
۳۳۱
Page 120
114
باب اول
وراثت کے مسائل
ترکہ کیسی شخصکی وفات پر اس کا امام اور فی تولہ جائیداد ترکہ کھلاتی ہے.وفات پر اس منظور وغیر منقولہ ترکہ.جب انسان فوت ہو جاتا ہے اور اپنا کچھ بال بطور ترکہ چھوڑ جاتا ہے تو اس ترکہ کو کیا کیا جائے
یہ ایک عالمگیر سوال ہے مذاہب عالم نے اس نے مختلف جواب دیئے ہیں اس سلسلہ میں اسلام نے جو
جواب دیا ہے اس کا مختصر ذکر درج ذیل ہے :-
تجهیز و تکفین ، قرض اور وصیت کی ادائیگی
جو ترکہ کسی متوفی نے چھوڑا ہے اسے اس کے وارثوں میں
تقسیم کرنے سے پہلے اس میں سے
على الترتيب مندرجہ ذیل ادائیگیاں کی جائیں گی :-
تجہیز و تکفین کے مصارف
۲ - قرض کی ادائیگی
۳ - وصیت کی ادائیگی
میت کے ترکہ میں سے سب سے پہلے اس کی تجہیز و تکفین کے اخراجات ادا کئے جائیں گے تجہیز و
تکفین ساده معروف رنگ میں سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کی جائے گی.اگر متوفی
کا ترکہ تجہیز و تکفین کے اخراجات کے لئے مکتفی نہ ہو تو حسب ضرورت یہ اخراجات بیت المال یا قومی
مرکزی فنڈ سے دو ہوں یعنی معاشرہ بحیثیت مجموعی ان اخراجات کا ذمہ دار ہوگا.۲- قرض کی ادائیگی
اگر متوفی کے ذمہ قرض ہو تو تجہیز و تکفین کے اخراجات کے بعد جو کچھ باقی بچے اس میں سے
سب سے پہلے قرض ادا کیا جائے گا.مہر بھی خاوند کے ذمہ واجب الادا قرض ہے.
Page 121
-۳- وصیت کی ادائیگی
A
1 - وصیت و ہی درست ہے جو بقائمی ہوش و حواس ہو...ب.اگر متوفی نے کوئی وصیت کی ہو تو ادائیگی قرضہ کے بعد اور قسیم ترکہ سے پہلے وہ وصیت ادا
ہوگی.ج - وصیت زیادہ سے زیادہ ترکہ کے ایک تہائی حصہ تک کی جاسکتی ہے.د وارث کے حق میں وقیت درست نہیں سوائے خاوند کے جو اپنی بیوی کی رہائش کے بارہ
کے حق سوائے خاوند کے جو اپنی پوری
میں وصیت کر سکتا ہے بلکہ ایسی وصیت کرنا اس کے لئے ضروری ہے لیے
باب دوم
ه
مانع میراث
ایسا امرمیں کی بناء پر ایک شخص جو عام حالات میں وارث بننے کا حقدار ہو وراثت سے محروم
ہو جاتا ہے مانع میراث کہلاتا ہے مثلاً
قتل :- قاتل اپنے مورث مقتول کے ترکہ کا وارث نہیں ہوگا کیونکہ حضرت ابو ہریرہ سے
روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القَاتِلُ لا يرٹ کر قاتل اپنے مقتول مورث کا
وارث نہیں ہو سکتا.تشریح
اسلامی نظامِ وراثت کی بنیاد رکھی رشتے ہیں انہی کی بنیاد پر وراثت جاری ہو گی بشرطیکہ
وارث اور مورث تناصر اور تضامن کے ایک سلسلہ میں منسلک ہوں چنا نچہ قرآن کریم کا ارشاد ہے :.سورة البقره آیت ۲۴۱
له ترندی ابواب الفرائض
Page 122
119
و أولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أولى بِبَعْضٍ فِي كِتَبِ اللهِ اِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
یعنی بعض رحمی رشتہ دار اللہ کی کتاب کی رو سے باہمی طور پر ایک دوسرے سے زیادہ قریب
ہوتے ہیں.اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے.ایک اور موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا :-
لَا يَنْهَكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِى الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِن
دِيَارِكُمْ اَنْ تَبرُوهُمْ وَتَقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَا إِنَّمَا
يَنْهُكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَاَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَهَرُوا
عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَهُمْ فَا وَلَبِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ٥
یعنی اللہ تم کو ان لوگوں سے نیکی کرنے اور عدل کا معاملہ کرنے سے نہیں روکتا جو
تم سے دینی اختلاف کی وجہ سے نہیں لڑے اور جنہوں نے تم کو تمہارے گھروں سے
نہیں نکالا.اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے.اللہ تم کو صرف ان لوگوں سے
گہری دوستی رکھنے سے روکتا ہے جنہوں نے تم سے دینی اختلاف کی وجہ سے جنگ کی
اور تم کو گھروں سے نکالا یا تمہارے نکالنے پر تمہارے دشمنوں کی مدد کی اور جو لوگ
بھی ایسے لوگوں سے دوستی کرئیں وہ ظالم ہیں.ب :.فقہاء اسلام نے قتل کے علاوہ میراث کے بعض اور مواقع بھی بیان کئے ہیں مثلا اختلاف
دین، اختلاف دارین کسی حادثہ میں ایک ساتھ فوت ہو جانا وغیرہ.لیکن ان اسباب
کو مانع قرار دینے
کی صحیح توجیہ یہ ہے کہ بعض اوقات یہ اسباب موانع بن جاتے ہیں خصوصا جبکہ اختلاف دین کی وجہ
سے با ہم سخت دشمنی پیدا ہو جائے اور نوبت جنگ و جدال تک جا پہنچے.ظاہر ہے کہ ایسے حالات میں
مختلف الدین افراد کی موالات یعنی باہمی دوستی کا معاہدہ اور ایک دوسرے کی نصرت جو باہمی میراث
کی اہم بنیاد ہے کیسے قائم رہ سکتی ہے.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ
แ
" لَا يَتَوَارَتْ أَهْلُ الْمَلَتَيْنِ شَتَّى " یعنی دینی اختلاف میں غلو کرنے والے جو تشقت اور
کے سورۃ الانفال آیت ۷۶
کے ابو داؤود كتاب الفرائض حي
می
سے سورۃ الممتحنہ آیت ۱۰۷۹
Page 123
تمتد فی تعصب کا شکار ہو گئے ہوں وہ ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوں گے.اسی طرح حدیث لا یرت
المُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الكَافِرُ الْمُسْلِمَ لے کا مفہوم مذکورہ بالا آیات قرآنی کی روشنی میں متعین ہو گا عینی
ایسے کافر جو حض مذہبی اختلاف کی بناء پر مسلمانوں سے جنگ کرتے ہیں اور ان کو ان کے گھروں سے نکالتے
ہیں وہ اپنے مسلمان مورث کے وارث نہیں ہوں گے.ایسی ہی بنیاد کے پیش نظر حضرت امیر معاویہ
نے اپنے عہد حکومت میں یہ قانون نافذ کیا تھا کہ کوئی نومسلم اپنے غیرمسلم مورث کی وراثت سے محروم نہیں
ہو گا یہ اس سے صاف ظاہر ہے کہ اختلاف دین کا مانع وقتی اور بعض مصالح کی بناء پر ہے.میں حال اختلاف دارین کا ہے یعنی ایسے دو ممالک جو آپس میں برسر پیکار ہوں یا ان میں
ایک دوسرے کے ملک میں ملکیت حاصل کرنے کا کوئی باہمی معاہدہ نہ ہو اُن ملکوں کے افراد آپس میں
رجمی رشتہ رکھنے کے باوجود ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوں گے.حادثہ میں اس طرح اکٹھے فوت ہونے والے افراد کہ ان کی موت کے وقت کا علم نہ ہوسکے انکے
ایک دوسرے کے وارث نہ بن سکنے کی بنیاد در اصل اس مفروضہ پر مبنی ہے کہ کیا معلوم کون پہلے فوت
ہوا ہے اور کون بعد میں لیکن فقہ الحد یہ اس بارہ میں اس اصول کو زیادہ صحیح مانتی ہے کہ حادثات
میں ایک ساتھ فوت ہونے والے رشتہ داروں کی وراثت کا مسئلہ اِس طور سے طے کیا جائے
کہ ان میں سے بڑی عمر والا پہلے فوت شدہ متصور ہو.مسلمان اور کا فر ایک دوسرے کے وارث نہیں ہو سکتے.(ابو داؤد کتاب الفرائض حت)
ه نرث اهل الكتاب ولا يرثونا انيل الأوطار باب امتناع الارث باختلاف الدين ص)
Page 124
۱۲۱
باب سوم
اصطلاحات
ذوى الفروض
ذوی الفروض سے مراد وہ وارث ہیں جن کے حصے قرآن کریم میں معین کر دیئے گئے ہیں.مثلاً
ماں، بیوی، خاوند وغیرہ.عصبات (عصبہ کی جمع)
عصبات سے مراد وہ وارث ہیں جن کا قرآن کریم نے کوئی حصہ معین نہیں کیا بلکہ ذوی الفروض
کو ان کے حصے دینے کے بعد بقیہ تمام تر کہ ان کو مل جاتا ہے اور اگر کوئی ذو الفرض نہ ہو تو سارا ترکہ ان میں
تقسیم ہوتا ہے مثلا بیٹا، پوتا ، باپ وغیرہ.عصبات کی اقسام
عصبہ کی تین قسمیں ہیں :-
ا عصبہ بنفسہ : عصبہ نفسہ سے میت کا وہ رشتہ دار مراد ہے جس کا متوفی سے تعلق براہ راست
ہو.عورت کے رشتہ کی وساطت نہ ہو مثلاً بیٹا، پوتا ، باپ، دادا، بھائی بھتیجا.اس کے بالمقابل نانا عصبہ
نہیں ہوسکتا کیونکہ ماں کے واسطہ سے رشتہ دار ہے اسی طرح نواسہ جس کا تعلق متوفی سے بیٹی کے واسطہ
سے ہے.Has
يعصبه بالغیر :- عصبہ بالغیر سے مراد مستوفی کی وہ رشتہ دار عورت ہے جو مرد کے واسطے
بنے.مثلاً بیٹی جو کہ بیٹے کی وجہ سے عصبہ بنتی ہے.پوتی جو کہ پوتے کی وجہ سے عصبہ بلتی ہے بہن
حقیقی ہو یا علاقی جو بھائی کی وجہ سے عصیبہ بنتی ہے.- عصبہ مع الغیر : متوفی کی وہ عورت رشتہ دار جو کسی دوسری عورت کے واسطے سے
Page 125
۱۲۲
عصبہ بن جاتی ہے لیے مثالی بہن جو متوفی کی بیٹی کے ساتھ مل کر عصبہ بن جاتی ہے.عصبات کی درجہ بندی
عصبات کی درجہ بندی الاقرب فالاقرب" کے اصول کے تحت ہے یعنی جن رشتہ داروں
کی قرابت متوفی سے زیادہ نزدیکی ہے وہ بوجہ عصبہ میراث میں مقدم ہوں گے اور نسبتا دور کے عصبات
محجوب ہوں گے.باعتبار قرب عصبات کی درجہ بندی حسب ذیل ہے :-
بیٹا ، پوتا، پڑپوتا وغیرہ (یعنی متوفی کی نسل)
ب باپ، دادا، پڑدادا (یعنی متوفی کی اصل)
ج- متوفی کا بھائی، بھائی کا بیٹا ، بھائی کا پوتا (یعنی متوفی کے باپ کی نسل )
- چچا، چا کا بیٹا، چا کا پوتا ( یعنی متوفی کے دادا کی نسل)
عصبہ کا حق میراث اُس کی قسم اور قرابت کے مطابق طے ہو گا مثلا
مذکورہ بالا چار اقسام میں اگر قسم اول کے عصبات موجود ہوں تو باقی قسموں کے عصبات وارث
نہیں ہوں گے.وعلی ہذا القیاس.اگر میراث سے حصہ پانے والے عصبات مرد اور عورت دونوں ہوں یعنی عصبہ نفسہ کے ساتھ
عصبہ بالغیر بھی ہو تو پر تقسیم لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِ الان ، کے اصول کے مطابق مرد کو عورت
سے دوگنا ملے گا.ذوی الارحام
ذوی الارحام سے مراد وہ وارث ہیں جن کا شمار نہ تو ذوی الفروض میں ہو اور نہ ہی عصبیات
میں بلکہ ان کی عدم موجودگی میں یہ وارث قرار پاتے ہیں مثلاً نواسہ بھونی، خالہ، ماموں.مثلاً ایک شخص فوت ہوتا ہے اس کے وارث ماں ، بیٹی اور بہن ہیں ماں کو ترکہ کا ہے ملے گا بیٹی کو
تو کہ کا یہ ملے گا اور بہن عصبہ ہو گی جسے ترکہ کا بقیہ حصہ ملے گا.لے سورة النساء : ١٣
Page 126
۱۲۳
باب چهارم
ا - والد
ذوی الفروض کے حصے
اگر متوفی کی اولاد ہو تو والد کو ترکہ کا پا حصہ ملے گا.ب - اگر متوفی کی لڑکی یا لڑکیاں موجود ہوں تو والد بطور ذوی الفروض یا حاصل کرے گا نیز دیگر
ذوی الفروض کو ادا کرنے کے بعد بقیہ ترکہ وہ بطور عصبہ حاصل کرے گا.ج - اگر متوفی کی اولاد نہ ہو تو والد عصبہ ہو گا یعنی تمام موجود ذوی الفروض کو ان کے حصے ادا کرنے
کے بعد جو بچ رہے گا وہ والد حاصل کرے گا اور اگر کوئی ذوی الفروض نہ ہو تو سارا ترکہ والد
-1
کو مل جائے گا.والده
اگر متولی کی اولاد ہو تو والدہ کو ترکہ کا یا حصہ ملے گا.ب.اگر متوفی کی اولاد نہ ہو لیکن میت کے بہن بھائی ایک سے زائد ہوں تو بھی والدہ کو ترکہ کا پا
اگر
حصہ ملے گا.اگر متوفی کی اولاد نہ ہو صرف والد اور والدہ ہوں اور کوئی بہن بھائی بھی نہ ہوں یا صرف ایک
بہن یا بھائی ہو تو والدہ کو ترکہ کا سا حصہ ملے گا.- اگر متوفی کی اولا دیا بہن بھائیوں میں سے کوئی بھی موجود نہ ہولیکن خاوند یا بیوی ہوں تو ان کا
معین حصہ ادا کرنے کے بعد والدہ کو باقی ترکہ کا سا حصہ ملے گا.دارا
اگر متوفی کا والد زندہ نہ ہو تو دادا کے حقوق میراث بعینہ وہی ہوں گے جو کہ والد کے ہیں
Page 127
۱۲۴
سوائے اس سے کہ متوفی کی اگر ماں زندہ ہو تو ماں کو کل ترکہ کا یہ بطور ذی الغرض ملے گا اور دادا
عصبہ ہوگا.۴ - جذات
اگر والدہ موجود نہ ہو تو دادی، نانی یا دونوں کو ترکہ کا پا حصہ ملے گا.۵.بیٹی
اگر متوفی کی ایک بیٹی وارث ہو تو اس کو ترکہ کا یہ حصہ ملے گا.ب.اگر دو یا دو سے زیادہ بیٹیاں ہوں تو ان کو یہ حصہ ملے گا.ج - اگر متوفی کی بیٹی کے علاوہ بیٹا بھی موجود ہو تو بیٹی عصبہ بالغیر ہوگی اور ترکہ ان کے درمیان
ایک اور دو کی نسبت سے تقسیم ہو گا یعنی بیٹی کو ایک حصہ اور بیٹے کو دو حصے ملیں گے.۶.پوتی
کو.اگر مستوفی کی اولاد بیٹا، بیٹی زندہ نہ ہو تو پوتی وراثت میں میٹی کے قائمقام ہوتی ہے.اگر
ایک ہوتی ہو تو اس کو ترکہ کا پا حصہ ملے گا اگر دو یا دو سے زائد پوتیاں ہوں تو ان کو ترکہ کا
حصہ ملے گا.ب.اگر متوفی کی ایک بیٹی اور ایک پوتی ہو تو ہوتی کو ترکہ کا حصہ ملے گا.ج - اگر متوفی کی ہوتی کے ساتھ پوتا یا پڑ پوتا بھی موجود ہو تو سب عصبہ ہوں گے جن میں ترکہ
لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَةِ الأَنتَيْنِ " کے اصول کے تحت تقسیم ہوگا.حقیقی بهین
و بہن بھائی تب وارث ہوتے ہیں جبکہ متوفی بھائی کے نہ کوئی نرینہ اولاد ہو اور نہ اس کے
باپ دادا زندہ ہوں یعنی نہ اس کی نرینہ اولاد ہو اور نہ اصل.بهر حال اگر متوفی کی نرینہ اولا دیا باپ دادا موجود ہوں تو حقیقی بھائی بہن کو کچھ نہیں ملے گا.ب.اگر متوفی کی اولا دیا باپ دادا بھائی میں سے کوئی موجود نہ ہو تو حقیقی بہن کو سے حصہ ملے گا.
Page 128
ج.اگر دو یا دو سے زائد حقیقی بہنیں ہوں تو ان
کو ترکہ کا یہ حصہ ملے گا.-2- اگر متولی کی بیٹیاں یا پوتیاں ہوں تو حقیقی میں عصبہ بن جائے گی یعنی ذوی الفروض کی ادائیگی
کے بعد بقیہ ترکہ اس کو ملے گا.8 - اگر متوفی کے حقیقی بھائی بھی موجود ہوں تو پھر بہنوں اور بھائیوں میں بحیثیت عصبہ تہ کہ ایک اور دو
کی نسبت سے تقسیم ہو گا.- علاقی سمن (دوسری والدہ سے بہن)
حقیقی بہن کی غیر موجودگی میں علاتی بہی کا حق میراث وہی ہے جو کہ حقیقی بہن کا ہے.اگر متوفی کی صرف ایک حقیقی بہن ہو تو علاقی بہن کو کچھ نہیں ملے گا البتہ ان کے ساتھ اگر علاتی
بھائی موجود ہو تو علاتی بہنیں بھی عصبہ بن جائیں گی اور ان سب میں بقیہ تر کہ ایک اور دو کی نسبت
سے تقسیم ہوگا یعنی مرد کے دو حصے اور عورت کا ایک حصہ ہو گا.۹ - خاوند
ور اگر متوفیہ کی اولاد موجود ہو تو خاوند کو ترکہ کا ہی حصہ ملے گا.ب - اگر متوفیہ کی اولاد موجود نہ ہو تو خاوند کو ترکہ کا یہ حصہ ملے گا.۱۰ - بیوی
1- اگر متوفی کی اولاد موجود ہو تو بیوی کو ایک ہو یا زائد ترکہ کا ہا حصہ ملے گا.ب - اگر اولاد موجود نہ ہو تو بیوی کو ( ایک ہو یا زائد) ترکہ کا یہ حصہ ملے گا.اختیافی (مادری) بہن بھائی
اگر متوفی کی نہ اولاد ہو نہ باپ دادا اور نہ ہی حقیقی یا علاتی بھائی بہنیں ہوں تو اخیافی (مادری)
نہ ہونہ پاپایا اور ان ای عالی بھائی ہوں تو
بہن بھائی حسب ذیل طریق پر وارث ہوں گے :-
-1- اگر منوٹی کا ایک اخیافی بھائی یا ایک اخیافی بہن ہو تو اس کو تو کہ کا پا حصہ ملے گا.ب.اگر متوفی کے دو یا دو سے زائد اخیافی بہن بھائی ہوں توسب ترکہ کے یا میں حصہ برابر شریک ہوںگے.
Page 129
۱۲۶
بات
پنجم
عصبات کے حصے
اگر ذوی الفروض موجود نہ ہوں تو کل ترکہ عصبات کو ملتا ہے.ب.اگر ذوی الفروض موجود ہوں تو ان کے حصص کی ادائیگی کے بعد بقیہ عصبات کو ملتا ہے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا " الْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لا ولى رَجُلٍ
ذکر ہے یعنی پہلے ذوی الفروض کو ان کے حصے دو اس کے بعد جو باقی بچے وہ توٹی کے قریبی مرد رشتہ دار
کو دو.باب
ششم
ذوی الارحام
ذوی الارحام سے مراد وہ رحمی رشتہ دار ہیں جن کا شمار نہ تو ذوی الفروض میں ہو اور نہ ہی
عصبات میں مثلا نواسہ ، نواسی بھانجا، بھانجی ، پھوپھی ، خالہ ، نانا ، ماموں وغیرہ.اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے :-
ل صحیح بخاری کتاب الفرائض باب ميراث الولد من أبيه و امه جلد ثانی 996
Page 130
۱۲۷
1 - وَاُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أولى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ اِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَى عَلِيمٌ
یعنی بعض رحمی رشتہ دار اللہ کی کتاب کی رُو سے باہمی رشتہ کے لحاظ سے ایک دوسرے
سے زیادہ قریبی ہوتے ہیں.اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے.ب.ایک اور جگہ فرمایا :-
واد احطَرَ الْقِسْمَةَ أولُوا الْقُرْنِي وَالْيَاتي والمسكين فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ
وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًات
اور جب ترکہ کی تقسیم کے وقت دوسرے قرابت دار اور یتیم اور مساکین بھی آجائیں
تو اس میں سے کچھ انہیں بھی دے دو اور انہیں مناسب اور عمدہ باتیں کہو.ان آیات سے اس استنباط کی تائید سنت رسول اور احادیث نبوی سے بھی ہوتی ہے چنانچہ
حضرت سعید بن منصور سے مروی ہے کہ
ثابت بن و جدائ جب فوت ہوئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیس بن عاصم
سے دریافت فرمایا کہ اس کی نسبت تم جانتے ہو ؟
قیس بن عاصم نے کہا یہ ہم میں غر تھا ہم صرف اس کے بھانجے کو پہنچانتے ہیں وہ
ابولبابہ بن مند رہے.چنانچہ ثابت بن وجدائی کی میراث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
نے اس کے بھانجے کو دلوا دی.ایک اور حدیث ہے :-
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
ابنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْ اَنْفُسِهِمْ -
حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قوم کا بھانجا
انہیں میں سے ہوتا ہے (یعنی بھانجے کو حق میراث پہنچتا ہے).د - ایک اور روایت ہے :-
الْغَالُ وَارِثُ مَنْ لا وَارِثَ لَه شم
سورۃ الانفال آیت ۷۶ له سورة النساء آیت 9 سے شریفیہ شرح سراجی طلا
که صحیح بخاری کتاب الفرائض ۹۹ ث ابن ماجه کتاب الفرائض جلدا ما
Page 131
۱۲۸
یعنی جس کا اور کوئی وارث نہیں تو پھر اس کا وارث اس کا ماموں ہوتا ہے.پس قرآن پاک اور سنت و حدیث سے ثابت ہے کہ جب ذوی الفروض اور عصبات میں سے کوئی
بھی موجود نہ ہو تو ترکہ ذوی الارحام میں تقسیم ہوتا ہے تاہم خاوند اور بیوی ذوی الارحام کی توریت
میں روک نہیں.یعنی اگر خاوند یا بیوی زندہ ہو تو ان کی موجودگی میں ذوی الارحام کو باقی ترکہ ملے گا
جبکہ دوسرے تمام ذوی الفروض ذوی الارحام کی توریت میں روک ہیں.ذوی الارحام کے درجے
عصبات کی طرح ذوی الارحام میں ترکہ کی تقسیم الأَقْرَبُ فَالا قرب" کے اصول کے تحت
ہوگی.ذوی الارحام کے چار درجے ہیں.ا.متوفی کی اپنی اولاد (جو نہ ذوی الفروض میں سے ہو اور نہ عصبات میں سے ، مثلاً نواسہ،
نواسی اور پوتیوں کی اولا در
-۲- متوفی کی اصل یعنی آبا ؤ اجداد جو نہ ذوی الفروض میں سے ہوں اور نہ عصبات میں سے ) مثلاً
نانا، باپ کا نانا ، دادی کا باپ، ماں کا دادا وغیرہ.متوفی نیے والدین کی اولاد رجونہ ذوی الفروض میں سے ہوا اور نہ عصبات میں سے ، مثلاً بھانجا
تو
بھانجی بھتیجی وغیرہ.۴.متوفی کے دادا اور نانی کی اولاد (جو نہ ذوی الفروض میں سے ہو اور نہ عصبات میں سے، مثلاً
پھوپھی ، ماموں، خالہ.پہلے درجے کے ذوی الارحام دوسرے ، تیسرے اور چوتھے درجے کے ذوی الارحام پر مقدم
ہوں گے.اسی طرح اگر پہلے درجے میں کوئی بھی موجود نہ ہو تو دوسرے درجہ کے ذوی الارحام تیسرے
اور چوتھے درجہ کے ذوی الارحام پر مقدم ہوں گے.وعلی ہذا القیاس.
Page 132
باب ہفتم
۱۲۹
رو
بعض حالات میں ذوی الفروض کو اُن کے مقررہ حصے ادا کرنے کے بعد کچھ ترکہ بیچ جاتا ہے
اور میت کا کوئی عصبہ موجود نہیں ہوتا جو یہ بچا ہوا تر کہ حاصل کرے چونکہ ذوی الارحام تو نبی
ذوی الفروض کی موجودگی میں حق میراث حاصل نہیں ہوتا اس لئے ایسی صورت میں باقی ماندہ تر کرنسی
ذوی الفروض کو ہی ان کے مقررہ حصوں کی نسبت کے لحاظ سے کوٹا دیا جاتا ہے اس طرز عمل کو رد کہتے
ہیں.نبی ذوی الفروض یہ ہیں :-
والدہ ، دادی، بیٹی ، پوتی، حقیقی بہن، علاتی بہن ، اخیافی بھائی..اس سے ظاہر ہے کہ خاوند یا بیوی کو بطریق رو زائد ترکہ نہیں ملے گا.باب شتم
عول
بعض دفعہ تقسیم ترکہ کے وقت ذوی الفروض
اتنی تعداد میں موجود ہوتے ہیں کہ ان کے
حصوں
کا مجموعہ اکائی سے بڑھ جاتا ہے اور یہ صورت اس وقت پیش آتی ہے جبکہ میت کے وارثوں
میں کوئی بیٹا یا پوتا یا پڑ پوتا وغیرہ موجود نہ ہو اگر یہ موجود ہوں تو ذوی الفروض کی تعداد یا تو گر جاتی
ہے یا ان کے حصے اس قدر کم ہو جاتے ہیں کہ ان کے حصوں کا مجموعہ اکائی سے کم رہتا ہے اور اس طرح
ترکہ کا خاصہ حصہ بیچے جاتا ہے جو عصبات (بیٹا، پوتا یا پڑ پوتا وغیرہ ) کو ملتا ہے.
Page 133
ایسے حالات میں اگر ذوی الفروض کے حصوں کا مجموعہ اکائی یا بالفاظ دیگر نسب نما یا مخرج سے
بڑھ جائے تو اس صورت میں تمام تر کہ کو ذوی الفروض کے حصوں کے تناسب سے تقسیم کریں گے
اس طرح پر ذوی الفروض اپنے معین حصے سے بحصہ رسدی قدرے کم حاصل کرے گا.مثلاً ایک متوفیہ
نے خاوند، د حقیقی بہنیں اور ماں وارث چھوڑے.اُن کے مقررہ حصے ، ہے اور پا ہیں جن کا مجموعہ
ہے جو اکائی سے بڑا ہے.اس صورت میں ان کے حصوں کا تناسب معلوم کریں گے جو ہے
کے لحاظ سے ۳، ۱،۴ ہے.اس طرح ترکہ کے گل آٹھ حصے کریں گے جن میں سے تین خاوند کو چار
بہنوں کو اور ایک ماں کو ملے گا.اس طریق سے ان کے حاصل کر دہ حصوں میں وہی نسبت قائم رہتی
ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہے.اِس طریق عمل کو عول کہتے ہیں.باب نهم
حمل کی میراث
جنین اپنے وفات یافتہ مورث کا وارث ہے بشرطیکہ وہ زندہ پیدا ہو لیں اگر کوئی شخص فوت
ہو جائے اور اس کی بیوی یا اس کے خاندان کی کوئی ایسی عورت حاملہ ہو جس کی اولاد کو میت کے ترکہ
میں سے حصہ پانے کا حق پہنچتا ہو تو ان حالات میں بہتر اور سہل صورت تو یہ ہے کہ وضع حمل کے بعد
ہی تو کر تقسیم کیا جائے لیکن اگر بعض ورثاء اس انتظار میں کچھ حرج تنگی یا ڈر محسوس کریں کہ کہیں ترکہ
ضائع نہ ہو جائے تو پھر موجودہ ورثاء قانونا ترک تقسیم کروا سکتے ہیں.اس صورت حال میں حسب ذیل
دو سوال پیدا ہوتے ہیں :."
لا - وضع حمل کے لئے زیادہ سے زیادہ کتنا عرصہ انتظار کیا جائے.ب- جاسکتا.اگر انتظار نہ کیا جا سکتا ہو اور ترکہ تقسیم کروانا مطلوب ہو تو ترکہ سے حمل کے لئے کتنا حصہ
محفوظ رکھا جائے.
Page 134
١٣١
پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ عام حالات میں مدت حمل طبتی شواہد کی بناء پر مقرر کی جائے گی لیے
دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ جو ترکہ بھی حمل کے لئے محفوظ رکھا جائے وہ بلحاظ تعداد و
کیفیت زیادہ سے زیادہ امکان کو مد نظر رکھ ک محفوظ کیا جائے.وضع حمل کے بعد اگر محفوظ کئے ہوئے حصّہ سے کچھ بچے جائے تو وہ وارثوں کو ان کے حصوں
کی نسبت کے لحاظ سے لوٹا دیا جائے گا اور اگر محفوظ کیا ہو ا حصہ کم ہو جائے تو ورثاء نومولود وارث
کو اس کے حصہ کے مطابق اپنے حاصل کردہ مال میں سے واپس کرنے کے ذمہ دار ہوں گے.اسی طرح اگر کسی وقت یہ ثابت ہو جائے کہ حمل نہیں تھا یا اسقاط ہو جائے یا بچہ مُردہ پید اہو تو
محفوظ کیا گیا ترکہ ورثاء میں ان کے حقوں کی نسبت کے لحاظ سے تقسیم کر دیا جائے گا.اگر یہ ثابت ہو
کہ بچہ کچھ دیر (یعنی چند لمحات) زندہ رہ کر فوت ہو گیا ہے تو اس صورت میں بچہ وارث ہو گا اور اس کا ترکہ
س نئے وارثوں میں تقسیم ہو گا.باب دہم
ه
عاونات
حادثات ، آفات سماوی یا جنگوں میں بظاہر ایک ساتھ فوت ہونے والے رشتہ داروں کا حکم.اگر کسی حادثہ میں ایک ساتھ بہت سے رشتہ دار فوت ہوں تو جو عمر میں بڑا تھا وہ پہلے فوت شدہ تسلیم کیا
جائے گا.اس طرح وہ مورث ہو گا اور چھوٹی عمر
کا وارث.ے زیادہ سے زیادہ تین سو دن مدت حمل سمجھی جاتی ہے.برطانوی عدالت میں سب سے زیادہ لمبا عرصہ حمل
۳۴۹ دن تک مانا گیا ہے.A TEXT BOOK OF MID WIFERY BY THONSTON'S KENER PAGE 110
نیز دیکھیں دفعہ نمبر۲۳ مع تشریح.
Page 135
باب یازدهم
۱۳۲
مفقود الخبر
مفقود الخر کومیت قرار دینے اور اس کی وفات
کی تاریخ معین کرنے کا حق قاضی کو ہے جو حسب
حالات فیصلہ کرے گا اور اسی کے مطابق وراثت اور دیگر شرعی احکام کا نفاذ ہو گا اس بارہ میں ملکی قانون
کو بھی مد نظر رکھنا مناسب ہے.بیٹے
باب دوازدهم
ولد الملاعنة
اگر خاوند اور بیوی میں نعان ہوا اور قاضی کے فیصلہ کے نتیجہ میں بچہ ان کی طرف منسوب ہو تو بچہ اور
مای کومہ باپ ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوں گے بلکہ یہ بچہ اور اس کی مانی ایک دوسرے کے وارث ہوں گے.باب سیزدهم
تیم پوتے انواس کی میشی
کوئی نقص صریح یتیم پوتے وغیرہ کی توری یا عدم توریت کی موجود نہیں البتہ معروف تعامل ہمیں یہی رہا ہے کہ چوں کی
موجودگی یں یتیم پوتا وغیرہ اپنے دادا کا وارث نہیں ہوتا تاہمار را نمی یک عمومی ترمیم کیا جائے کوئی یتیم و اونتی پیر
محروم امارت نہیں رہ سکتے اور اگر داد کسی اتفاقی حادثہ کی وجہ سے وصیت ن کر سکے تو قاضی یہ ترکہ تک ایسے مقامی کو دلاسکتا ہے
بشرطیکہ دیگر ورثاء کو نقصان نہ پہنچے.تمت بالخير فالحمد لله رب العلمين
لے مرتفصیل کے لئے دیکھئے بحث مفقود الخبر دفہ نمبر ۴۲ کے مثلاً اس کے باپ کو میراث میں سے جو حصہ ملتا وہ کم ہو اس سے
جو اُسے وصیت کی صورت میں مل رہا ہے.گویا اصول یہ ہوا کہ وصیت اس کے میراث کے حصہ سے زیادہ نہ ہو؟