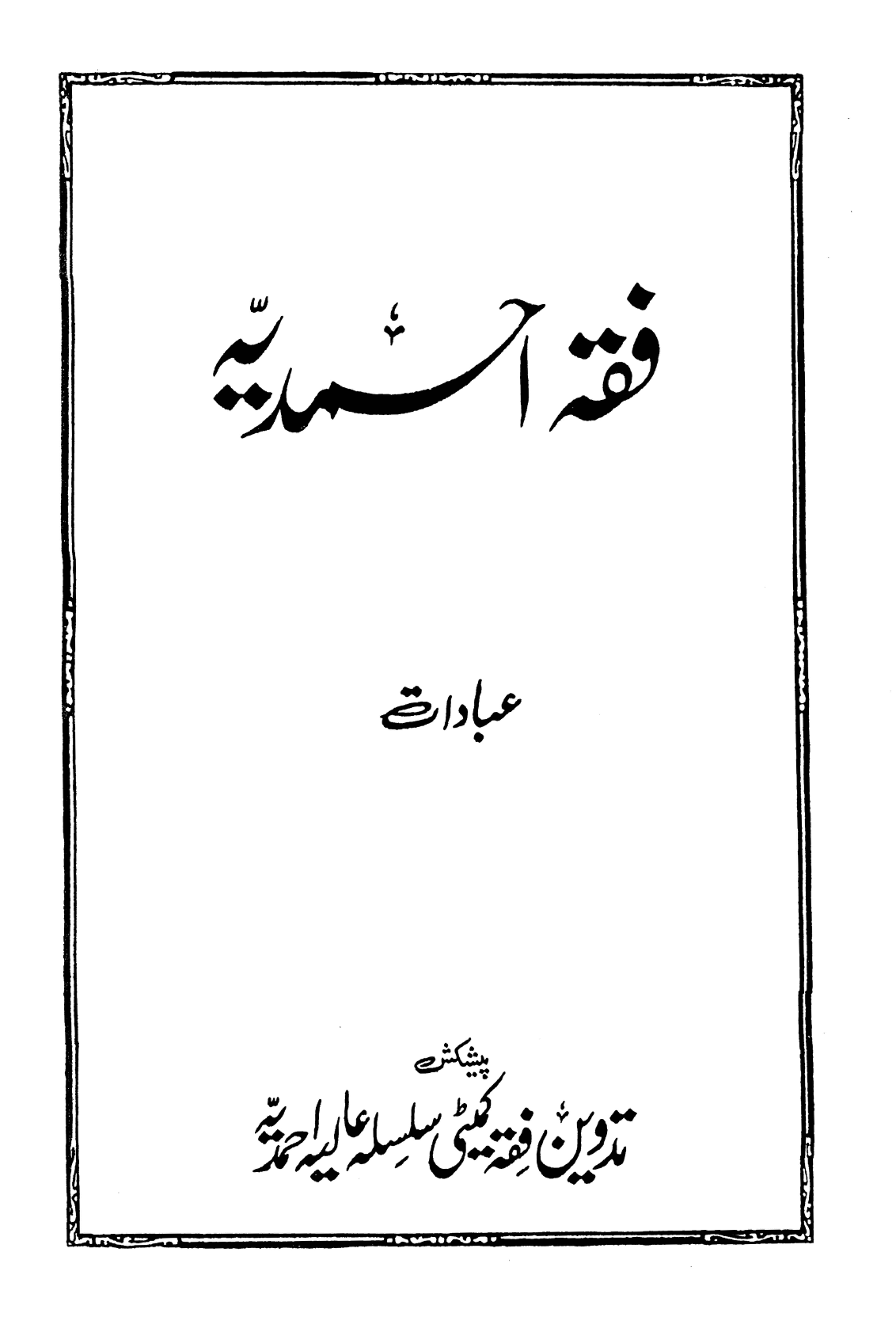Complete Text of FiqahAhmadiyya Part1
Content sourced fromAlislam.org
Page 1
فقة المادية
عبادات
پیشکش
تدوین فقہ بیٹی سلسلہ عالیہ حدی
Page 2
نام کتاب
پیشکش
فقہ احمدیہ (حصہ عبادات)
تدوین فقہ کمیٹی سلسلہ عالیہ احمدیہ
نظارت نشر واشاعت، ربوه
طبع اوّل ، دوم وسوم
حالیہ اشاعت
مئی 2004 ء
زیر اہتمام
ان بالا به نظارت نشر و اشاعت، قادیان
نشرواشاعت
تعداد
3000
مطبع
پر نویل پریس، امرتسر
Presented by:
FIQAH AHMADIYYA
(Hissa Ibadaat)
Tadween Fiqah Committee Silsila Aaliya Ahmadiyya
First, Second & Third Edition Published by:
Nazarat Ishaat, Rabwah.Present Edition in India 2004
Copies : 3000
Published by:
Nazarat Nashro Ishaat, Qadian
Printed at
Printwell, 146 Industrial Focal Point
Amrtisar.ISBN: 81-7912-059-7
Page 3
نمبر شماره
عنوان
فہرست مضامین
عنوان
صفح
جزو اول
نماز
شریعت اور عبادت
عبادت اور اس کے معنے
عبادت کی ضرورت
عبادت کا مجموعی فلسفہ
عبادت کی اقسام
ارکان اسلام
نماز کی اہمیت
نماز کا فلسفہ
اقامت الصلوة
صلاۃ کے معنے
نمانہ اور دعا
1
۱۲
۱۴
۲۲
۲۵
نماز میں فریق حصول حضور
جنده و دوم
نماز کی شرائط
نمانہ کی پہلی شرط.وقت
اوقات نمازہ کی حکمت
اوقات مکروہہ
نماز کی دوسری شرط - طہارت
موجبات غسل
نہانے کے فرائض و آداب
بیت الخلاء اور استنجاء
موجبات وضو
وضو کرنے کا طریق
فرائض وضو
قبولیت دعا کی عظمت پر ایک فعلی شهادت
نماز اور ذ کہ مالی
خلاصة
۲۹
سفن وضو
وضور کی حکمت
جرابوں پر مسح کرنا
۳۴
✓
۴۹
۴۹
조금
۴۵
۵۱
۵۲
무무무
۵۳
۵۲۳
۵۳
۵۲
Page 4
".عنوان
تیم اور ان کی مسائل
پانی اور اس کے مسائل
طہارت
برکات وضو
نماز کی تیسری شرط
ستر عورت یعنی پرده پوشی
نماز کی چوتھی شرط قبلہ
قبلہ کی حکمت
نماز کی پانچویں شرط - نیست
صفحہ
۵۵
۵۶
۵۷
A<
۶۴
S
۶۸
۶۹
عنوان
صفح
مکروہات نمانه
مبطلات نماند
مشتبهات
سجدہ سہو
نماز کی اقسام اور ان کی رکعات
دعا اور سجدہ
رکوع و سجود میں قرآنی دعا
دعا بين السجدتين
نماز با جماعت اور 1
بلند آواز سے دعا
نماز کے بعد دعا
نماز پڑھنے کا طریق تسبیح پھرنا
نماز
طریق نمانه
نماز میں ہاتھ باندھنا
رفع یدین
دعائے استفتاح الصلاة
+ +
5
44
۸۲
۸۲
جره و چهارم
لاذان
متفرقات
اقامت
نماز با جماعت
نماز سے تعلق بعض افعال کی تفصیل ۸۹ نماز با جماعت کی حکمت
44
۹۹
모음을
۹۴
90
1-1
11.١١٣
۱۱۴
114
A
۱۲۴
۱۲۵
۱۲۹
۱۳۰
۱۳۲
۱۳۴
۱۳۵
بلند یا آہستہ قرأت کی حکمت
نمانہ یا جماعت کی اہمیت
امام الصلوة کا تقریر
اجرت پر امام الصلواة کا نتقرام
۹۱
۹۲
۹۲
۹۳
اله کان نمانه
واجبات نماز
سنن نماز
مستحبات نمازه
Page 5
عنوان
امام الصلوۃ مقرر کرنے کی شرائط
غسال کے پیچھے نمازہ
مجذور امام
نا بالغ امام
عورت اور امامت صلوۃ
امام الصلواۃ پر اعتراض
امام کے کھڑا ہونے کی جگہ
اصفحه
۱۳۵
۱۳۵
۱۳۷
۱۳۸
۱۳۹
7.عنوان
صفحہ
غیر معمولی علاقوں میں اوقات نماز ۱۵۸
نماز جمعہ
141
نمازہ جمعہ کا طریق
خطبہ ثانیہ کے مسنون الفاظ
جمعہ کی فرضیت و اہمیت
سفر اور جمعہ
۱۳
امام مقتدیوں کا خیال رکھے ۱۴۰
دو آدمیوں سے جمعہ کی نمازہ
امام کا انتظار
خطبہ کھڑے ہو کہ دینا
دوسری جماعت
امام کی انتباع
امام کی غلطی
امام سے پہلے سلام پھیرنا
نمانه با جماعت اور قرأة
۱۴۳
۱۴۱
۱۴۷
۱۴۷
۱۴۸
خطہ کا اختصار
1<
K.نماز جمعہ اور ریڈیو
خطبہ کے دوران میں بولنا
جمعہ اور عید کا اجتماع
۱۷۴
164
جمعہ کے بعد احتیاطی نمازہ
فاتحہ خلف الامام.نماز عیدین
جماعت سے رہی ہوئی رکھتیں ۱۵۳
قربانی کے مسائل
نماز میں کسی آیت کا تکرار
آیات کی ترتیب
۱۵۴
۱۵۴
عقیقہ
14A
TAY
(AM
نمازیں جمع کرنا
قرآن کریم کا جلدی جلدی پڑھنا ۱۵۴
نماز سفر
قرأۃ میں امام کی غلطی
امام
کی غلطی نما نہ میں
نماز اور زبان
ریڈیو پر نمانه
100
100
104
104
سفر اور قصر
سفری تاجہ کی نماز
1AQ
14°
معلم
حکام کا دورہ سفر نہیں
نماز خوف
۱۹۳
۱۹۴
Page 6
ا صفحه
صفحه
عنوان
عنوان
جنگ اور نمازہ
190
فوت شدہ نمازیں اور انکی قضاء ۱۹۶
قضائے عمری
وتر
نماز وتر کے متعلق فتاوی
وتر پڑھنے کا وقت
سفر ملی و تمر
وتر اور قرأة سور
وتروں کے بعد نقل
وتر با جماعت
نماز تہجد
نماز تراویح
نماز کسوف و خسوف
نماز استبقاء
نمایند استخاره
صلوة الحاجة
نماز اشراق
صلوة التسبيح
سجدہ تلاوت
144
14<
149
۳۰۰
۲۰۱
۳۰۲
۲۰۲
۲۰۳
۲۱۱
۳۱۳
۲۱۴
۲۱۵
کی مسجد کے لئے چندہ
مسجد کی زینت
مسجد اور مدرسہ
مسجد اور اس میں سستانے کی اجازہ
مسجد اور تنازعہ
تعظیم قبله
نماز جنازہ
۲۲۹
۲۳۵
نمازہ جنازہ کی مسنون دعائیں ۲۳۹
متفرقات
سم ۲۴
غسل میت طاعون زده
طاعون زدہ کو کفن
۲۴۵
نماز جنازہ میں چار سے زیادہ تکبیریں
مشتبہ المحال
شخص کا جنازہ
غیر مبالع کا جنازہ
بچوں کا جنازہ
غیرمسلم کی وفات اسلامی معاشرہ میں
جنازہ غائب
نماز جنازہ کا تکرار
۲۴۹
۲۵۱
۲۵۱
Par
مسجد میں میت رکھ کر نماز جنازہ ۲۵۵
آداب مسجد
مسجد کی جگہ تبدیل کرنا
۲۱۹
۲۲۰
مسجد کا ایک حصہ مکان میں ملانا
مسجد اور رہائشی کوارتر ۲۲۲
زیارت قبور
مردوں کے لئے دعا کرنا
قبر میں سوال و جواب
مردوں کو سلام اور ان کا سننا
۲۵۸
Page 7
عنوان
ا صفحه
مردہ کی آوانہ
مرنے پہ کھانا کھلانا
دسویں محرم کو خیرات
مردہ کے لئے قرآن خوانی
مردہ کا ختم و اسقاط میت
گردہ کی استقاط
میت کے لئے قل
مردہ کی فاتحہ خوانی
ختم اور ختم کی ریوڑیاں
مرده پر نوحہ
فیر علی بتانا
ما
۲۶۱
۲۲۱
۲۶۲
FYM
۳۶۳
۲۶۳
۲۶۴
۲۶۴
۲۶۵
صفح
عنوان
روزہ رکھنے اور افطار کرنیکا وقت ۲۷۲
روندہ کسی چیز سے افطار کرنا چاہیئے
نواقض روزه
وہ امور جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ۲۷۸
روزہ نہ رکھنے والے
فتاوی
چاند دیکھنے کا غیر طبعی طریق
۲۷۹
روزہ اور نیست
سفیدی میں نیت روزه
PAY
سفر میں روزہ کی ممانعت کی وضات ۲۸۸
روزہ رکھ کر سفر شروع کرنا
خلاصہ
۲۸۹
۲۸۹
قبر یا روضہ بنانا
مزار کو بوسہ دینا
روزه
قدیم مذاہری میں روزہ
روزہ کی غرض
روزہ رکھنے والے کا درجہ
روزوں کی اقسام
رمضان کے روزے
روزہ کس پر فرض ہے
روزہ کب رکھنا چا ہیئے
۲۶۹
٣٠٣
روزہ کے لئے نیت ضروری ہے ۲۷۴
ہمارا اور مسافر
روزہ رکھنے کی عمر
۳۹۰
مرضعہ حاملہ بچہ اور طالبعلم ۲۹۱
بعض پرانی بیماریاں
ندیه توفیق روزہ کا موجب ہے ۲۹۳
ندیه
۲۹۴
دائمی مسافر اور مریض کا فدیہ ۲۹۷
جان بوجھ کر روزہ نوٹہ نا
ایسے امور جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ۲۹۹
روزہ کی حالت میں بھول کر کھانا ۳۰۰
غیر معمولی علاقوں میں اوقات روزه ۳۰۱
Page 8
عنوان
صفحه
اعتکاف
اعتکاف کی اہمیت
۳۰
۳۰۵
فتاوی
حج
۳۱۵
فلسفه حج
مقامات حج
اوقات حج
حج فرض ہونے کی شرائط
الدكان حج
حج کرنے کا طریق
۳۲۰
۳۳۰
۳۳۰
۳۳۱
۳۳۱
احرام
عمره
حج کی اقسام
جنایات حج
احصار
متفرق مسائل
فتاوی
حج بدل
عنوان
ام
۱۳۴۲
زكوة
۳۴۹
انفاق فی سبیل اللہ کی اقسام ۲۵۱
زکواۃ اور انکم ٹیکس میں فرق
۳۵۳۱
زكواة وصدقات اور قرآنی ارشادات ۳۵۴
زکوۃ واجب ہے
اموال زکواة
۳۵۸
شرائط وجوب تكراة
نصاب و شرح زكوة
الرسم
زمین کی پیداوار کا نصاب و شرح ۳۶۲ کی
۳۳۵
۳۳۵
۳۳۷
۳۳۹
۳۴۰
جانوروں کا نصاب و شرح
۳۶۳
متفرق مسائل
فتاوی
مصارف زکواة
سید کے لئے زکواۃ
۳۴۴۱
Page 9
عرض حال
فتنہ احمدیہ کے اس حصہ کو محترم مرزا عبد الحق صاحب ایڈووکیٹ صدر تدوین
محمد احمد صاحب مظہر ایڈووکیٹ صدر مجلس افتاء - محترم سید
ن کمٹی اور محترم.میر داؤد احمد صاحب مرحوم نے پوری توجہ سے بالاستیعاب دیکھا اور مرواری
اصلاحات تجویز فرما دیں اور مفید مشور سے دیئے.نجز اہم اللہ تعالیٰ احسن الجزاء -
فرما دیں
ان مشوروں کو کتاب کی تسوید میں پوری طرح ملحوظ رخسا گیا."
علاوہ ازیں حوالجات کی تلاش تصحیح چھان بین میں محترم سید شمس الحق صاحب
معاون مفتی دار الافتاء - محترمہ محمد یوسف صاحب سلیم محترم عبد الماجد صاحب طاہر
اور محترم منیر احمد صاحب جا دیا.اساتذہ جامعہ احمدیہ نے قابل شکریہ تعاون
فرمایا.فجزاهم الله تعالیٰ احسن الجزاء :
خاکسار
ملک سیف الرحمن
ناظم دار الافتاء در توه
Page 10
جز اول
اسلامی شریعت اور عبادت
عبادت اور اس کے معنے
عبادت کی ضرورت
اسلامی عبادت کی اقسام
ارکان اسلام
نماندہ کی اہمیت
نماز کا فلسفہ
اسلامی نماز
اقامت الصلاة - اقامت کے معنے.صلاۃ کے معنے
نماز اور دعا
قبولیت دعا کی عظمت پر ایک فعلی شہادت
نمازہ اور ذکر الہی
خلاصہ
Page 11
اسلامی شریعیت اور عبادت
قرآن کریم کوئی انوکھی تعلیم پیش نہیں کرتا بلکہ وہ اس اندرونی شریعیت کو یاد دلاتا ہے جواللہ تعالی نے
انسان کے اندر مختلف طاقتوں کی صورت میں ودیعت کر رکھی ہے.اس شریعت کے ذریعہ انسان کے
اندرونی قولی خصوصا اس کی قوت شہوانیہ اور قوت غضبیہ کی تہذیب و تعدیل ہوتی ہے جس کے نتیجہ میں
مختلف اخلاق پیدا ہوتے ہیں مثلاً علم ہے ایشیا ر ہے صبر ہے قناعت ہے سخاوت ہے شجاعت ہے
اطاعت ہے اخلاص ہے صدق ہے دیانت ہے محنت ہے اور عمل صالح کی استعداد ہے.غرض جو
فطرت قدرت نے باطن میں رکھی تھی.قرآن نے اُسے یاد دلایا ہے جیسے فرمایا :-
ا
" في كتاب مكنون" له
یعنی صحیفہ فطرت میں جو چھپی ہوئی کتاب تھی اور جس کو ہر ایک شخص نہ دیکھ سکتا تھا اس کو اس وحی
نے سب کے سامنے کھول کر رکھ دیا اور اس کی پوری پوری وضاحت کر دی.یہ ہے اسلامی شریعت اور
قرآن کریم کی علی تعلیم کا تصور جس کی تشریح و تفصیل زندگی کے تمام پہلوؤں پر حاوی ہے اور اسی کا
ایک اہم حصہ عبادت سے متعلق ہے جو اس وقت ہمارے زیر بحث
عبادتے اور اُسے کے معنے
گفت کے لحاظ سے عبادت کے معنے تابع بن کہ اعلیٰ ہستی کے ساتھ ساتھ چلنے ، اسے
تعلق کے اظہار میں سرگرمی دکھانے ، اس کا نمونہ بن جانے ، اس کی اطاعت میں اپنے وجود کو لگا دینے
اس کی مہربانیوں کے گن گانے اور اس کے احسانوں کا شکریہ ادا کرنے کے ہیں ظاہر ہے کہ عجز و نیاز
خضوع و خشوع ، تذلل و انکسار، فروشتنی و عاجزی ، فدائیت و ممنونیت ان معنوں کا لازمی نتیجہ ہے.فدائیت کے اس مفہوم کو ایک شاعر نے یوں ادا کیا ہے :-
" تمہار سے حسین ازلی ، تمہاری جود و سخا اور تمہار سے انعام واکرام نے میری تین چیزیں
جیت لی ہیں یعنی میرا دل، میری زبان اور میرا جسم ، دل تمہاری عظمت کا اعتراف
کرتا ہے
الواقعہ :
49 :
Page 12
زبان تمہاری حمد کے گیت گاتی ہے اور جسم تمہار سے احترام میں جھک گیا ہے.لے
پس عبادت کے ان معنوں سے ظاہر ہے کہ عبادت صرف اللہ تعالی کی ہو سکتی ہے کیونکہ وہی ہر
لحاظ سے کامل ہے تمام خوبیوں کا جامع اور تمام انتمائص سے پاک ہے وہ رب العالمین ہے.رحمان اور رحیم ہے.مالک یوم الدین ہے اس کا ساتھ تمام کامیابیوں کا منبع ہے اور اس کا تعلق
سب تعلقات پر فائق ہے وہی ایک ہستی ہے جس کی اطاعت پر انسانیت مجبور ہے وہ محسن ازلی
ہے سزا وار حمد وشکر ہے.اسی کی مہربانیوں کے انسان گن گاتا ہے اور اس کے احسانوں پر
فدا ہے اس کا حسن از بی عشق انگیز ہے اس کے رنگ میں رنگین ہونا انسانیت کے لئے باعث
فخرو زینت ہے اسی کے حضور انسانیت مجھک سکتی ہے کیونکہ اس کے سامنے جھکنا انسانیت
کا معراج ہے یے اور اس کے سوا کسی اور کے سامنے جھکنا اور اس کے حضور تذلل و انکسار اختیار
کرنا نہ صرف یہ کہ انسانیت کے شایان شان نہیں بلکہ یہ اس کی توہین ہے.عبادت کی ضرورت
کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عبادت ایک لغو فعل ہے نہ صرف یہ کہ اس
کی ہمیں کچھ ضرورت نہیں بلکہ یہ
ایک مضر کام ہے اس
سے خوشامد اور چاپلوسی کی عادت پڑتی ہے یا حرص و لالچ بڑھتا ہے لیکن یہ
سب اعتراض بجائے خود لغو ہیں.ایسے اعتراض کرنے والے دراصل فطرت انسانی سے بے خبر
ہیں اور حقیقت سے بہت دُور جا پڑے ہیں کیونکہ اگر ہم عبادت کے مذکورہ بالا معنوں پر غور کریں تو
ان اعتراضات کی لغویت خود بخود ظاہر ہو جائے گی اور ان کی کچھ حقیقت باقی نہیں رہے گی پھر جیسا
کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی حسین چیز یا خوشنما منتظر سامنے آئے تو بے اختیار اس کی تعریف کرنے
اس کے قرب میں جانے بلکہ بعض اوقات اس پر فدا ہونے کو دل چاہتا ہے چاہے ہمیں اس سے
کچھ فائدہ حاصل ہو یا نہ ہو.پس جب بے تعلقی کی صورت میں حسن کے متعلق انسانی فطرت کا یہ حال
ہے تو جہاں حسین کامل اور احسان تام اور خالق و مخلوق ہونے کا رشتہ تینوں جمع ہوں وہاں حمد و ثناء
اور شکر و امتنان کے لئے کیوں دل بے اختیار نہ ہوگا اور کیوں اس پر فدا ہونے کو جی نہیں چاہیے
گا.حقیقت یہ ہے کہ عبادت یعنی محسن کی حمد و ثناء اور اس پر فدا ہو جانے کی خواہش انسان کی
فطرت کا ایک حصہ اور اس کی ضمیر کی ایک آواز ہے وہ اس کے ارتقاء کی سیڑھی ہے اسی راستہ
سے وہ اپنے مقصد پیدائش تک پہنچتا ہے.له افادتكم النعماء منى ثلثة يدى ولساني والضمير المحدباً تد الصلاة معراج المؤمن وتفسير ايران
ه اول :
Page 13
عبادت کی بنیادی غرض و نسال الہی ہے.اسی سے اُسے خُدا شناسی کا نغ ملتا ہے اور خُدا
سے اس کے تعلق کا اظہار ہوتا ہے اس کی روحانیت ترقی کرتی ہے.اطمینان کی دولت نصیب
ہوتی ہے یہاں تک کہ انسان حقیقی معنوں میں عبد یعنی خدا نما وجود بن جا" ہے جو روحانیت کا
ایک اعلیٰ مقام ہے.پس عبادت کوئی چٹی نہیں نہ اس میں خوشامد اور چاپلوسی والی کوئی بات ہے اور نہ لالچ و حرص
کا کوئی تحریکی اندانہ عبادت سے اللہ ذوالجلال کا کوئی ذاتی فائدہ وابستہ نہیں اور نہ ہی اسے اس
کی ضرورت ہے.اگر کوئی اس کی عبادت نہ کر سے تب بھی اس کی خدائی میں کچھ فرق نہیں آئے گا.جس طرح انسان کے پیدا کرنے میں اس کا کوئی ذاتی فائدہ نہیں.اسی طرح عبادت کے تقاضا کو
اس کی فطرت میں رکھ دینے اور اُس کے لئے اس کی راہنمائی کرنے میں بھی اس کا کوئی ذاتی فائدہ
نہیں یہ محض اس کا فضل و کرم اور اس کی ربوبیت کا فیضان ہے کہ اُس نے اپنے بندوی کو پیدا
کیا اور پھر ان کی راہنمائی فرمائی اور عبادت کے ذریعہ اپنے آپ
کو مکمل کرنے کی راہیں ان کیلئے کھول دیں.غرض عبادت میں بندہ کا اپنا فائدہ اور اُس کی اپنی بھلائی ہے.اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے :-
وَ مَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَلَى بِنَفْسِهِ اله
یعنی جو شخص گناہوں میں ملوث ہونے سے بچتا ہے اور پاکیزگی اختیار کر تا ہے وہ اپنا ہی فائدہ
کرتا ہے.عبادت کا عمو نے فلسفہ
جیسا کہ اوپر اشارہ آچکا ہے کہ انسان کو اس لئے پیدا کیا گیا ہے، تاکہ اس کے ذریعہ خالق دو جہاں
کے وجود کا ظہور اور اس کی صفات کا نمود ہو.اللہ اور فطرت اور بہانہ ہائے قدرت خاش ہو جائیں کھل کر سامنے
آجائیں یعنی انسان خدا نما وجود ہے اور اس طرح اس کا مظہر بن کر تخلیق کائنات کی غرض و غایت کو پورا کرے
اسی لئے انسان کو عبد کہا گیا ہے کیونکہ عبادت کے ایک معنے کسی کے نقش کو قبول کرنے کے ہیں اور انسان
کو ایسے ملکوتی قوی اور اعلیٰ اقدار ودیعت ہوئے ہیں جن کی مدد سے وہ صفات الہیہ کا پورا نقشہ پیش
کر سکتا ہے اور ان کو اپنے اندر پیدا کر نے کی پوری پوری اہلیت رکھتا ہے.شد
اللہ تعالیٰ قرآن کریم نہیں فرماتا ہے :
وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون
فاطر: ۱۹ که عربات الصادقين طلاء ملفوظات جلد ششم طه تفسیر کبیر جلد اول جز اول با لغات القرآن :- ذاریات به
Page 14
یعنی میں نے جن و انس کو صرف عبادت کے لئے پیدا کیا ہے یعنی اس لئے کہ تا وہ میرے ظہور
کا موجب اور میری صفات کا مظہر نہیں.اس آیہ کریمہ کی تفسیر وہ حدیث قدسی کرتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :.كُنتُ كثرًا مَغْفِيًا فاردت أن أغرَن.له
یعنی میں ایک مخفی خندانہ تھا پھر میں نے ارادہ کیا کہ میں پہچانا جاؤں اور دُنیا میں جانا جاؤں
اس لئے میں نے آدم کو پیدا کیا.اس کی مزید وضاحت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں ہے."إِنَّ اللهَ خَلَقَ أَدَمَ عَلَى صُورَتِهِ لَه
یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا.ان ارشادات کا یہی مطلب ہے کہ انسان
کی پیدائش کا مقصد ذات باری کا ظہور اتم ہے کیونکہ وہ صفات الہیہ کا مظہر بن سکتا ہے.اور
اس کی قدرت کے اسرار پر سے پردہ اٹھانے کی ذہنی استعداد لے کر پیدا ہوا ہے.یہی وجہ ہے
که استنباط، ایجادات اور نئے نئے انکشافات کی جو قابلیتیں انسان کو ودیعت کی گئی ہیں وہ کسی
دوسری مخلوق کو عطا نہیں ہوئیں.اسی مفہوم کی عمومیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سیدنا حضرت سیح
موعود علیہ السّلام فرماتے ہیں :-
خدا تعالی کی ذات میں اپنی عظمت، اپنی خدائی، اپنی کبریائی ، اپنا جلال ، اپنی
بادشاہی ظاہر کرنیکا ایک تقاضا پایا جاتا ہے اور سزا و جزا اور مطالبه اطاعت و عبودیت و پرستش
اسی تقاضا کی فرع ہے اسی اظہار ربوبیت و خُدائی کی غرض سے یہ انواع و اقسام کا
عالم ارنسی پیدا کر رکھا ہے ورنہ اگر اس کی ذات میں یہ جوش اظہار نہ پایا جاتا تو پھر
وہ کیوں پیدا کرنے کی طرف ناحق متوجہ ہوتا اور کس نے اس کے سر پر بوجھ ڈالا تھا کہ
ضرور یہ عالم پیدا کر رہے اور ارواح کو اجسام کے ساتھ تعلق دے کر اس مسافرخانہ
کو جو دنیا کے نام سے موسوم ہے اپنی عجائب قدرتوں کی جگہ بنا ہے.آخر اس میں کوئی
قوت اقتضاء تھی جو اس بنا ڈالنے کی متحرک ہوئی اسی کی طرف اس کے پاک کلام
میں جو قرآن شریف ہے اشارات پائے جاتے ہیں.جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خدا تعالٰی
نے کل عالم کو اس غرض سے پیدا کیا کہ تا وہ اپنی خالقیت کی صفت سے شناخت کیا
جائے اور پھر پیدا کرنے کے بعد اپنی مخلوقات پسر حم و کرم کی بارشیں کیں تادہ رحیمی و کریمی
کی صفت سے شناخت کیا جائے ایسا ہی اس نے سزا و جزا دی تا اس کا منتظم اور نظم
مية
- مزيل النحفاء والا لباس جلد ۲ ملا مصنفہ اسمعیل بن محمد العجلانی سے بخاری کتاب استان باید الایمانداری والالباس - شه به نیست
Page 15
ہونا ایسا کیا جائے......غرض وہ اپنے عجیب کاموں سے یہی مدعا رکھتا ہے کہ نادہ
پہچانا جائے اور شناخت کیا جائے سو جبکہ دنیا کے پیدا کرنے اور جزا و سزا وغیرہ سے
اصلی غرض معرفت الہی ہے جو لب لباب پرستش و عبادت ہے تو اس سے صاف
ثابت ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ خود تقاضا فرماتا ہے کہ تا اس کی معرفت جس کی حقیقت کا ملہ
پرستش و عبادت کے ذریعہ سے گھلتی ہے.اس کے بندوں سے حاصل ہو جائے جیسا کہ
ایک خوبصورت اپنے کمال خوبصورتی کی وجہ سے اپنے حسن کو ظاہر کرنا چاہتا ہے سو خدا تعالیٰ
جس پر جس حقیقی کے کمالات ختم ہیں وہ بھی اپنے ذاتی جوش سے چاہتا ہے کہ وہ کمالات
لوگوں پر کھل جائیں لے
عبادت کے ایک اور معنے کسی کا بن جانے اس کے سامنے بچھ جانے اس میں فنا ہو جانے اس
کے حضور تذکل اختیار کرنے اور اس کا کہنا ماننے کے ہیں اور انسان بھی اپنے وجود کو ایک بالا راستی
کے سامنے مٹا دینے اس کی محبت میں فنا ہو جانے اور اس کا ہی بن جانے کی پوری پوری صلاحیت
رکھتا ہے اس لئے اُسے عبد کہا گیا ہے.پس ان معنوں کے لحاظ سے عبادت صرف ایسی کا مل ہستی ہی کی ہو سکتی ہے جو اپنے کمالات
میں منفرد ہو اور اس کا کوئی شریک نہ ہو اور جس کی اطاعت اور فرمانبرداری کا انسان ہر حال
میں پابند ہو ایسی ذات صرف اللہ تعالٰی کی ہے کیونکہ اس کے سوا کوئی نہیں جس کی حقیقی معنوں
میں فرمانبرداری کی جا سکے اور جس کی ذات کو چین کہ انسان اُسی کا ہو جائے اور اُسی کی پناہ کے نیچے
اپنے آپ کو لے آوے.حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ کا عبد کہلانے کی ایک راہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے حضور
اپنے جذبات شکر کا اظہار کرے اور اس کے احسانوں کا اپنی زبان سے اقرار کرے کیونکہ انسان فطرتاً
اپنے محسن کا شکریہ ادا کر نے پر مجبور ہوتا ہے جیسا کہ حدیث میں آتا ہے.جبلت القُلُوبُ عَلَى حُبِّ مَنْ أَحْسَنَ إِلَيْهَا له
یعنی انسان کی بناوٹ ہی ایسی ہے کہ وہ اپنے محسن سے محبت کرنے پر مجبور ہوتا ہے.اللہ تعالیٰ
کا حقیقی عبد بننے کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ انسان گناہوں اور بدیوں سے نجات پا جائے
اپنے دل کو پاک کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک لوگ ہی اس کی بارگاہ میں بار پاسکتے ہیں
یہی وجہ ہے کہ تمام مقررہ عبادات میں اس بات کو مد نظر رکھا گیا ہے کہ ان کے ذریعہ نفس انسانی
ے ا سرمه چشم آمریه ۲۱۵-۲۱۹ سے :- جامع الصغیر جلد اول ما بحوالہ بیہقی فی شعب الایمان :
Page 16
بدیلوں سے پاک ہو جائے اور اُسے ایسی طاقت مل جائے کہ وہ مختلف قسم کے ہوا و ہوس کو چھوڑنے کے
قابل ہو جائے.ایک طرف اللہ تعالٰی سے اس کے تعلقات درست ہو جائیں اور دوسری طرف مخلوق
الہی سے اس کے معاملات بالکل درست اور صاف رہیں یہ
عبادت کے دو حصے ہیں ایک خدا کا خوف اور دوسرے خدا سے محبت.یہ دونوں باتیں انسان
کو پاکیزگی کے چشمہ کی طرف لے جاتی ہیں اور اس کی روح گداز ہو کر الوہیت کی طرف بہتی ہے اور
عبودیت کا حقیقی رنگ اس میں پیدا ہو جاتا ہے اور دنیا کی ساری محبتوں
کو فانی اور آنی سمجھ کر
وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کو دنیا میں حقیقی محبوب یقین کرنے لگ جاتا ہے.خوف اور محبت دو ایسی چیزیں ہیں کہ بظاہر ان کا جمع ہونا محال نظر آتا ہے کہ ایک شخص جسے
خوف کرے اس سے محبت کیونکہ کر سکتا ہے مگر اللہ تعالیٰ کا خوف اور محبت ایک الگ رنگ کھیتی ہے
جس قدر انسان خُدا کے حروف میں ترقی کرے گا اسی قدر خدا تعالیٰ کا خوف غالب ہوگر بدیوں اور
اور برائیوں سے نفرت دلا کہ پاکیزگی کی طرف لے جائے گا.اور جوں جوں وہ محبت الہی میں ترقی کرتا
جائے گا عبادت میں اُسے ایک لذت و سرور حاصل ہوگا ہاں ایسی لذت اور ایسا سرور جو دنیا کی
تمام لذتوں اور تمام خطوظ نفس سے بالا تر اور بلند ہے.(۲)
اسلام عبادت کو چار اصولی اغراض میں تقسیم کرتا ہے :-
(۱) وہ عبادت جس کی غرض اللہ تعالٰی کے ساتھ محبت اور اس کے ساتھ تعلق بڑھانا ہے.، وہ عبادت جو انسان کے جسم کی اصلاح اور اُسے قربانیاں دینے پر آمادہ کرنے کیلئے ہوتی
ہے اور جس سے روح ایک خاص جلاء حاصل کرتی ہے.(۳) وہ عبادت جو انسانوں کے اندر مرکزیت کی روح اور اتحاد ویگانگت کا احساس پیدا کرنے
کے لئے مقرر کی جاتی ہے.(۴) وہ عبادت جو بنی نوع انسان کی اقتصادی حالتوں میں یکسوئی اور یک رنگی پیدا کرنے کے لئے
مقرر کی جاتی ہے.اسلام عبادت کی یہ چارہ اصولی اغراض مقرر کرتا ہے اور ان اغراض کے مطابق اس نے
مختلف عبادتیں مقرر کی ہیں اور اس اصول
کو تجویز کر کے اسلام نے یہ نظریہ پیش کیا ہے کہ عبادت
صرف اسی بات کا نام نہیں کہ انسان خدا تعالیٰ کی طرف دھیان لگائے بلکہ بنی نوع انسان کی طرف
توجہ کرنے سے بھی خدا تعالیٰ کی عبادت کا فرض ادا ہوتا ہے.اسی طرح اسلام نے یہ نکتہ بھی پیش کیا ہے کہ
ب : - تفسير كبير ملخصاً ٣٣٣٥
Page 17
عبادت صرف انفرادی نہیں بلکہ وہ اجتماعی بھی ہوتی ہے.انسان کا صرف یہی فرض نہیں کہ وہ خدا تعالیٰ
کے سامنے پیش ہو جائے بلکہ انسان کا یہ بھی فرض ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کو بھی خدا کے سامنے
پیش ہونے کے لئے تیار کر رہے.اس لئے قرآن کے جتنے احکام عبادات کے متعلق ہیں وہ
انفرادی بھی ہیں اور اجتماعی بھی.لہ
اسلامی عبادت کی اقسام
اصولی طور پر عبادت دو قسموں میں منقسم ہے.عام عبادت اور خاص عبادت.عام عبادت
کا تعلق بالعموم حقوق العباد سے ہے.اس لحاظ سے انسان جو کام بھی خواہ وہ
ذاتی ہو یا اجتماعی.خدا وند تعالیٰ کی خاطر اور اُس کی رضا حاصل کرنے کے لئے کہ سے اور وہ خدمت
انسانیت سے متعلق ہو اسلامی نظریہ کے مطابق وہ عبادت ہے اور اس پر ثواب اور نیک جزا کا
وعدہ دیا گیا ہے مگر اسی نقطہ مرکزی کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھتے، اسے اپنی عادت بنا لینے اور
عبادت کے بنیادی مقاصد کو صحیح معنوں میں حاصل کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خاص
عبادت کا بھی حکم دیا ہے.یہ خاص عبادت پانچ حصوں میں منقسم ہے جنہیں ارکان اسلام کہتے
ہیں یعنی اسلام کے ایسے ستون جن پہ اسلام کی عمارت استوار ہے.ارکانِ اسلام
ارکان اسلام میں سے پہلا رکن کلمہ شہادت ہے.یعنی یہ اعتراف کرنا اور گواہی دیا کہ اللہتعالیٰ
کے سوا کوئی معبود و محبوب نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں وہی اللہ تعالیٰ کا پیغام
لائے ہیں اور اسلام کے سارے احکام انہوں نے ہی آکر بتائے ہیں.ان الہ کان میں سے دوسرا رکن نماز پڑھنا.تیسرا زکواۃ دینا.چوتھا رمضان کے روزے
رکھنا اور پانچواں خانہ کعبہ کی زیارت کے لئے مکہ جانا یعنی حج کرنا ہے.اسلام کے ان پانچوں
ارکان کی تفصیل سید نا حضرت عمرض کی ایک روایت سے معلوم ہوتی ہے جس میں آپ بیان
کرتے ہیں کہ ایک دن حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام نہ کے درمیان تشریف فرما تھے
۴۵۲
لے: دیباچہ تفسیر القرآن ص :
Page 18
۱۲
کہ ایک شخص آیا.اس کی زلفیں کالی تھیں صاف ستھر سے اُجلے کپڑے پہنے ہوئے تھا بالکل معلوم
نہیں ہوتا تھا کہ وہ کہیں باہر سے سفر کر کے آیا ہے نہ اس کے کپڑے پیلے تھے اور نہ ہی اس کے ہاتھ
پاؤں پر گرد و غبار کا کوئی نشان تھا لیکن ہم میں سے کوئی بھی اُسے نہ جانتا تھا.اس لئے ہم حیران
تھے کہ یہ شخص کون ہے.وہ بادب دوزانو ہو کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیٹھ گیا
سب سے پہلے اس نے یہ سوال کیا کہ اسلام کیا ہے.حضور نے فرمایا.اسلام یہ ہے کہ تو گواہی
دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اس کے رسول ہیں.دوسرے تو نماز پڑھے تیر سے زکواۃ
دے.چوتھے رمضان کے روز سے رکھے.پانچویں اگر تجھے استطاعت ہے تو بیت اللہ کا عمر بھر
میں ایک بارہ حج کر ہے.اس پر اُس شخص نے کہا حضور پیچ فرماتے ہیں.ہم پہلے ہی حیران تھے اب اور بھی اچنبھا ہوا کہ عجیب انسان ہے خود ہی پوچھتا ہے
اور خود ہی صیاد بھی کرتا جاتا ہے.پھر اُس نے پوچھا.ایمان کیا ہے ؟ حضور نے فرمایا.ایمان یہ
ہے کہ تو اللہ تعالی پیدائش کے فرشتوں پر.اس کی کتابوں پر اور اُس کے رسولوں
پر ایمان لائے
اور آخری دن پر یقین رکھے اور خیر و شر کے انداز سے اور اس کے بر محل ہونے پر تیرا ایمان ہو.پھراس نے پوچھا.احسان کیا ہے ؟ حضور نے فرمایا.احسان یہ ہے کہ واللہ تعالیٰ کی اس طرح
عبادت کرے کہ گویا تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے اور اگر تجھے یہ مقام حاصل نہ ہو سکے تو پر کم از کم تجھ میں یہ
احساس ضرور ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تجھے ہر وقت دیکھتا ہے اسی طرح کے چند اور سوالات اس نے کئے
اور حضور نے ان کے جوابات دیئے.اس کے بعد وہ چلا گیا.حضرت عمر بیان کرتے ہیں کہ اُس کے چلے
جانے کے بعد حضور نے میری طرف دیکھ کر فرمایا.عمر ! تم جانتے ہو یہ کون تھے ؟ یہ جبریل تھے جو
تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے.یہ
اس تفصیلی روایت سے ظاہر ہے کہ اسلام کا دوسرا اہم رکن نماز ہے اور اس کے تفصیلی احکام
کو بیان
کرنا اس وقت ہمارے پیش نظر ہے.نماز کی اہمیت
اللہ تعالی قرآن کریم میں نماز پڑھنے کی بار بار تاکید کرتا ہے اور باقاعدگی سے نماز پڑھنے
والوں کی تعریف اور نہ پڑھنے والوں یا اس میں شکستی برتنے والوں کی مذمت کرتا ہے.چنانچہ وہ
فرماتا ہے.رحمان خُدا کے سچے بند سے وہ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں اور اس پر
ترمذی کتاب الایمان باب في وصف جبریل النبی صلی الله عت مشکواۃ کتاب الایمان صلا : سه : الميمتون ۱۰ :
Page 19
مداومت اختیار کرتے ہیں یہ اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا ہے.نمازوں کی حفاظت کرو خصوصاً
اس نماز کی جو کام کاج کے درمیان میں آئے یہ پھر فرمایا.جو نماز نہیں پڑھتے وہ دوزخ میں جائیں
گے یہ نماز میں کسل مندی اور سستی اختیار کر نے والوں کی حالت قابل افسوس ہے کیے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی نماز کی بڑی تاکید اور فضیلت آئی ہے.چنانچہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں.نماز دین کا ستون ہے جینسی نمانہ با قاعدگی سے پڑھی انس
نے دین کو قائم کیا اور جس نے اُسے ترک کیا اُس نے دین کو گرایا اور اس کی عمارت منہدم
کر دی.اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی نماز ہے.ایک بار فرمایا قیامت کے دن سب
سے پہلے نمازہ کا حساب لیا جائے گا.ایک اور موقع پر صحابہ کے سامنے تھانہ کی فضیلت بیان
کرتے ہوئے فرمایا جس شخص کے دروازے کے پاس سے صاف شفاف پانی کی نہر بہتی ہو
اویہ وہ اس میں دن میں پانچ بار نہائے جس طرح اس کے بدن پر میل نہیں رہ سکتی اسی طرح
اس شخص کا باطن بھی ناصاف نہیں رہ سکتا اور نہ اس میں کوئی کر درست یا گناہ کی میل رہ سکتی
ہے.جو دن میں پانچ وقت نماز پڑھتا ہے شیہ
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ سب سے اہم فریضہ میرے نز دیک نماز ہے
جس نے اُسے ضائع کیا اُس نے سب کچھ ضائع کر دیا یعنی ایسی حالت میں اس شخص کا کوئی بھی
کارنامہ قابل ستائش نہیں سمجھا جا سکتا.سید نا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں :-
و نما نہ ہر ایک مسلمان پر فرض ہے حدیث شریف میں آیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کے پاس ایک قوم اسلام لائی اور عرض کی کہ یا رسول اللہ ! ہمیں نماز معاف فرما
دی جائے کیونکہ ہم کاروباری آدمی ہیں مویشی وغیرہ کے سبب سے کپڑوں کا کوئی اعتماد
نہیں ہوتا اور نہ ہمیں فرصت ہوتی ہے تو آپ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ دیکھو
جب نمازہ نہیں تو ہے ہی کیا ؟ وہ دین ہی نہیں جس میں نمازہ نہیں.نما نہ کیا ہے ؟
یہی کہ اپنے عجز و نیانہ اور کمزوریوں کو خُدا کے سامنے پیش کرنا اور اس سے اپنی
حاجت روائی چاہنا کی بھی اس کی عظمت اور اس کے احکام کی بجا آوری کے
واسطے دست بستہ کھڑا ہونا اور کبھی کمال مذلت اور فروتنی اسے اس کے آگے سجدہ
میں گر جانا اس سے اپنی حاجات کا مانگنا ہی نمازہ ہے.ایک سائل کی طرح کبھی اس
- المعارج : ۲۲ سه : - البقرة : ۲۳۹ ۳: - المدثر : ۲۳ ، ۲۴ سه : - الماعون : ۶۷۵ که : بخاری مواقیت الصلوة -
Page 20
مسئول کی تعریف کرنا کہ تو ایسا ہے تو ایسا ہے اس کی عظمت و جلال
کا اظہار کر کے اسکی
رحمت کو جنبش دلانا پھر اس سے مانگنا.پس جس دین میں یہ نہیں وہ دین ہی کیا
ہے انسان ہر وقت محتاج ہے اس سے اس کی رضا کی راہیں مانگتا رہے اور اس
کے فضل کا اسی نخواستگار ہو.......خدا تعالیٰ کی محبت اسی کا خوف اسی کی یاد میں
دل لگارہنے کا نام نمازہ ہے اور یہی دین ہے.لہ
" خدا تعالیٰ تک پہنچنا منزلی منزل ہوتا ہے جس میں انسانی محنت ، کوشش
جدوجہد کی ضرورت ہوتی ہے اس طرح منزل مراد تک پہنچنے کے لئے یعنی قرب
اہی حاصل کرنے کے لئے نمانہ ایک گاڑی ہے جس پر سوار ہو کر وہ جلد خدا تعالیٰ
کو یا سکتا ہے اور جنبی نمازہ ترک کی وہ کس طرح خُدا کو پا سکتا ہے" ہے
اسی طرح ایک اور جگہ حضور فرماتے ہیں :-
" نماز سے بڑھ کر اور کوئی وظیفہ نہیں کیونکہ اس میں حمد الہی ہے.استغفار
ہے اور درود شریف تمام وظائف اور اوراد کا مجموعہ یہی نمازہ ہے اور اس
سے ہر قسم کے غم وہم دُور ہوتے ہیں اور مشکلات حل ہوتی ہیں...نماند کو سنوار سنوار کر اور سمجھ سمجھ کر پڑھو اور مسنون دعاؤں کے بعد اپنے لئے اپنی
زبان میں بھی دعائیں کرو اس سے تمہیں اطمینان قلب حاصل ہوگا اور سر
مشکلات خدا تعالیٰ چاہے گا تو اس سے حل ہو جائیں گی نمازہ یاد الہی کا ذریعہ ہے اسی
لئے فرمایا.آدمِ الصَّلوةَ لِذِكْرِى تے
نماز
کا فلسفہ
اصل عبادت دل کی کیفیت اور اس کے ماتحت انسانی اعمال کے صدور کا نام ہے اور
چونکہ انسانی بناوٹ اس قسم کی ہے کہ جسم کا اثر روح پیر اور روح کا اثر جسم پر پڑتا ہے.مثلاً ہم
دیکھتے ہیں کہ جو شخص غمگین صورت بنا لیتا ہے یا غمگین لوگوں میں بیٹھتا ہے تھوڑی دیر کے بعد
اس کا دل بھی غم سے بھر آتا ہے ایسے ہی اگر وہ یونہی ہنسنے کی کوشش کرتا ہے یا خوش کیف
لوگوں میں بیٹھتا ہے تو کچھ دیر کے بعد اس کے دل میں بھی مسرت کے جذبات ابھرنے لگتے ہیں.اس کے برعکس اگر انسان کا دل صدمہ اور غم سے دو چار ہو تو جسم مرجھا جاتا ہے.آنکھوں میں آنسو
فوری ص ۲۵ ۲۵۳ - محفوظات مفہوما ص ۲۵ : که له : ۱۵ ، ملفوظات ص۳۳۳۳۳ :
ای
:
Page 21
10
آجاتے ہیں.بال جلد سفید ہو جاتے ہیں مگر اس کے برخلاف خوشی سے چہرہ نکھر آتا ہے اس
پر بشاشت کے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں جسم میں ایک تازگی اور چستی محسوس ہونے لگتی ہے
سو انسان کی اس فطرتی کیفیت اور اس کے اس طبعی قانون کے مطابق اسلام نے نماز میں چند
افعال و اقوال شامل کئے ہیں تاکہ وہ ظاہری ہیتیں جن سے ادب کا اظہار ہوتا ہے اس کے
باطن میں بھی یہی جذبات پیدا کر دیں اور اس کے بالمقابل روح کا تذلیل اور انکساران حرکات
ادب کے پیدا کرنے کا موجب بنے.پس نماز کے ظاہری اعمال و اقوال ، خاص اوقات کی تعیین قبلہ رو ہونا، ہاتھ باندھ کر
کھڑا ہونا.رکوع وسجود کرنا صرف قلبی کیفیت کو بدلنے کے لئے مقرر ہیں.اور یوں بھی کہ سکتے ہیں
کر ان قلبی کیفیات ہی کے یہ نتائج ہیں یہ
•
یاد رکھیئے نمانہ کوئی چٹی نہیں بلکہ نمازہ اس لئے مقرر کی گئی ہے کہ یہ انسانوں کو ہر قسم کے
نقصان سے بچاتی اور بدیوں سے روکتی ہے گویا اسلام یہ نظریہ پیش کرتا ہے کہ اسے انسان تو
نماز پڑھ اس لئے نہیں کہ تیرا خُدا چاہتا ہے کہ دس پندرہ منٹ کے لئے تو اوٹھک بیٹھک
کر سے بلکہ اس لئے کہ یہ تمہاری اصلاح کا موجب ہے اور یہ بدیوں کو مٹانے والی چیز ہے.بعض لوگ باوجود نماز پڑھنے کے پھر بدیاں کرتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ وہ نمازیں
پڑھتے ہیں مگر نہ روح اور راستی کے ساتھ وہ صرف رسم اور عادت کے طور پر ٹکریں مارتے ہیں.ان کی روح مردہ ہے وہ نماز بدیوں کو دور کرتی ہے جو اپنے اندر ایک سچائی کی روح رکھتی ہے اور
فیض کی تاثیر اس میں موجود ہے.نماز صرف ظاہری نشست و برخاست کا نام نہیں بلکہ ارکان نماند
در اصل روحانی نشست و برخاست ہیں انسان
کو خدا تعالیٰ کے روبرو کھڑا ہونا پڑتا ہے اور قیام
بھی آداب خدمتگار ان میں سے ہے.رکوع جو دوسرا حصہ ہے بتلاتا ہے کہ گویا تیاری ہے کہ وہ
تعمیل حکم میں کسی قدر گردن جھکاتا ہے اور سجدہ کمال آداب اور کمال تذتل اور مستی کو جو عبادت
کا مقصود ہے ظاہر کرتا ہے یہ آداب اور طرق ہیں جو خدا تعالیٰ نے بطور یادداشت کے مقرر کر دیئے
ہیں اور جسم کو باطنی طریق سے حصہ دینے کی خاطر ان کو مقرر کیا ہے.علاوہ انہیں باطنی طریق
اثبات کی خاطر ایک ظاہری طریق بھی رکھدیا ہے اب اگر ظاہری طریق میں صرف نقال کی طرح نقلیں
اتاری جائیں اور اسے بارہ گراں سمجھ کر اتار پھینکنے کی کوشش کی جاو سے تو تم ہی بتاؤ اس میں کیا
لذت اور حظ آسکتا ہے اور جب تک لذت اور سرور نہ آئے اس کی حقیقت کیونکہ تحقیق ہوگی
تفسیر کبیر :
کے
Page 22
I
اور یہ اسی وقت ہوگا جبکہ روح بھی ہمہ نیستی اور تذلل تام ہو کر آستانہ الوہیت پر گرے اور جو
زبان بولتی ہے روح بھی بولے اس وقت ایک سرور اور نور اور تسکین حاصل ہو جاتی ہے.الفرض نمازہ انسان کی اندرونی غلاظتوں کو پانی کی طرح ومعد کہ صاف کہتی ہے روح پگھل کر
پانی کی طرح آستانہ الوہیت پر بہنے لگتی ہے.نماز میں رکوع یہ ہے کہ انسان تمام قسم کی محبتوں
اور تعلقات کو چھوڑ کر خدا تعالیٰ کی طرف جھک جائے اور صرف خدا تعالیٰ کے لئے ہو جائے اور روح
کا سجدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آستانہ پر گر کر اپنے تئیں نکلی کھو دے اور اپنے نفس وجود کو مٹا
رے
نماز میں لذت اور سرور بھی عبودیت اور ربوبیت کے ایک تعلق سے پیدا ہوتا ہے جب تک
اپنے آپ کو عدم محض یا مشابہ با لعدم قرار د سے کہ جو ربوبیت کا ذاتی تقاضا ہے نہ ڈال دے اس کا
فیضان اور پر تو اس پر نہیں پڑتا اور اگر ایسا ہو تو پھر اعلی درجہ کی لذت حاصل ہوتی ہے جسے
بڑھ کر کوئی حق نہیں ہے.اس مقام پر انسان کی روح جب ہمہ نیستی ہو جاتی ہے تو وہ خدا تعالیٰ
کی طرف ایک چشمہ کی طرح بہتی ہے اور ماسوی اللہ سے اُسے انقطاع تام ہو جاتا ہے اس وقت
خدا تعالیٰ کی محبت اس پہ گرتی ہے.اس اتصال کے وقت ان دو جوشوں سے جو اُوپر کی طرف سے
ریوبیت کا جوش اور نیچے کی طرف سے عبودیت کا جوش ہوتا ہے ایک خاص کیفیت پیدا ہوتی ہے
اس کا نام صلاۃ ہے.پس یہی وہ صلاۃ ہے جو سیئات کو بھسم کر جاتی ہے اور اپنی جگہ ایک نور اور چھک چھوڑ
دیتی ہے جو سالک کو راستہ کیسے خطرات اور مشکلات کے وقت ایک منور شمع کا کام دیتی ہے اور
ہر قسم کے خس و خاشاک اور ٹھو کر کے پچھتروں اور خاروفس سے جو اس
کی راہ میں ہوتی ہیں آگاہ
کر کے بچاتی ہے اور یہی وہ حالت ہے جب کہ اِنَّ الصَّلوةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِه
کا اطلاق اس پر ہوتا ہے کیونکہ اس کے ہاتھ میں نہیں اس کے دل میں ایک روشن چراغ رکھا
ہوا ہوتا ہے اور یہ درجہ کامل تذلل - کامل نیستی اور فروتنی اور پوری اطاعت سے حاصل ہوتا ہے
پھر گناہ کا خیال اُسے کیونکر آسکتا ہے.انکار اس میں پیدا ہی نہیں ہو سکتا.فحشاء کی طرف
اس کی نظر اُٹھ ہی نہیں سکتی ہے
پس نمانہ روحانی ترقیات کا منبع ہے.اس میں ہمیں یہ سبق دیا گیا ہے کہ ہم صرف اللہ تعالے کو
اپنا آقا یقین کریں.صرف اسی کو اپنا رازق سمجھیں اور ہر کام میں اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کریں
:- العنكبوت : ۴۶
ه : ملفوظات ۱۶۳ تا ۴۶۶
1
Page 23
اور جو کچھ بھی کریں خدا کی رضا کے مطابق کریں اور دنیا کے دھندوں میں پھنس کر اُسے فراموش نہ
کریں بینچ اٹھتے ہی نمازہ ہمیں یہی بات یاد دلاتی ہے اس کے بعد ہم کام کاج میں مشغول ہو جاتے
ہیں لیکن وقفے وقفے کے بعد اس یاد کو تازہ کیا جاتا ہے.یہاں یہ کہ جب ہم رات کو سونے لگتے
ہیں تو آخری بار پھر اسی کا اعادہ ہوتا ہے.کلام الی اقم الصلوة کذکری » یعنی میری یاد کو
تازہ رکھنے کے لئے نماز قائم کہ میں اسی یاد کی طرف اشارہ ہے.فرین کو مستعدی سے بجالانے کے لئے ضروری ہے کہ انسان کو اس کام کی عادت ہو.فوجوں
کو روزانہ بار با نہ قواعد کرانے میں یہی حکمت ہے ورنہ مستعدی باقی نہیں رہ ہے گی اس حکمت کے
پیش نظر بھی دن میں متعدد نمازیں فرض کی گئیں تاکہ مسلمانوں کا بار بار امتحان لیا جاتا رہے کہ وہ
اپنے دعوی کے مطابق واقع میں بھی مستند مسلمان ہیں یا کہ نہیں.نمانہ خداوند تعالیٰ کے خوف اور اس کے حاضر و ناظر اور علیم و خبیر ہونے کا یقین آدمی کے
دل میں بٹھاتی ہے اور اس یقین کو تازہ کرتی رہتی ہے تاکہ ہم اپنے کام کاج میں اللہ تعالی کی رضا سے
غافل نہ ہوں.کیونکہ جو شخص بار بار خدا کے حضور میں جاکر یہ اقرار کر سے گا کہ اسے خدا تو تمام خوبیوں کا
مالک ہے سب کا پروردگا ر ہے بے انتہاء کریم کرنے والا اور سچی محنتوں کا اجر دینے والا ہے.جزا و سزا تیرے ہی اختیار میں ہے.میں تیرا بندہ ہوں.تجھے اپنا مالک اپنا رازق سمجھتا ہوں.تیری فرمانبرداری کا دم بھرتا ہوں تو ایسا شخص لازما گنا ہوں سے تائب ہو جائے گا کیونکہ یہ کیسے
ممکن ہے کہ ایک شخص خدا کو رب العالمین.رحمن و رحیم - مالک یوم الدین اور علیم و خبیر با کیم تقدیر
بھی یقین کر سے اور پھر برائیاں بھی کرنا پھر سے اور بار بار اس کے دربار میں جانے سے بھی نہ شرمائے.نماز میں اللہ تعالٰی کے احکام سے واقفیت حاصل کر نے کا بھی موقع ملتا ہے کیونکہ نمانہ میں قرآن
پاک کا کچھ نہ کچھ حصہ پڑھا جاتا ہے اس طرح روزانہ اللہ تعالٰی کے کتنے ہی احکام کے متعلق ہمارا اعلم
تازہ ہو جاتا ہے اور اسی عمل کرنے کی مزید تحریک پیدا ہوتی ہے.نماز ہمیں یہ سبق بھی دیتی
ہے کہ جو کام ہمارے سپرد ہے وہ کسی ایک فرد واحد کے بس کی بات نہیں اس کے لئے اجتماعی
قوت درکار ہے.جب تک سب مل کہ پوری یک جہتی اور کامل اتحاد کے ساتھ اسلام کے غلبہ
کی کوشش نہ کریں گے اسلام غالب نہیں ہو گا.ہر قوم میں کوئی نہ کوئی طریق خدا تعالیٰ کی عبادت کا مقرر ہے مگر ضروری نہیں کہ اس طریق
میں کوئی معقولیت اور حکمت بھی ہو لیکن اسلامی طریق عبادت یعنی نماز کے تمام افعال و حرکات با غرض
Page 24
۱۸
بافائدہ اور باوقار ہیں اور اس میں پڑھے جانے والے تمام اقوال با منے اور پر از ما ہیں.اس طرح نمازمیں
تمام وہ طریق تعظیم اختیار کئے گئے ہیں جو مختلف اقوام میں اظہا ر ادب کے لئے استعمال ہوتے ہیں.ایرانی اقوام میں ہاتھ چھوڑ کر سیدھا کھڑا ہو جانا اظہا ر ادب کی علامت تھا.ترکی نسل کی اقوام میں ہاتھ
باندھ کر کھڑا ہوجانا اظہار ادب کی علامت تھا.یہودیوں اور بعض دوسری اقوام میں جھکتا اظہار عقیدت کی علامت
تھا.بر صغیر پاک و بھارت اور افریقہ میں سجد سے کے طور پر گر جانا اظہار ادب کا طریق.یورپین اقوام میں
گھٹنے کے بل بیٹھ جانے کو اظہا ر ادب کا طریق سمجھا گیا.غرض ہر قوم میں اظہار عقیدت کی کوئی نہ کوئی علامت
محسوس و مشہور ہے.نماز میں ان تمام آداب کو جمع کر دیا گیا ہے.اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ جب کسی مذہب کا کوئی شخص مسلمان ہوگا اور نماز میں اپنے قومی شعار
کو دیکھے گا اور اس میں اظہار ادب کے اپنے مخصوص و مانوس طریق کو اختیار کر لے گا تو اسے کمال لذت
محسوس ہوگی.عیسائی گھٹنے کے بل جھک جانے یعنی تشہد کی طرز کو پسند کرتا ہے کیونکہ عیسائیوں میں اظہار
ادب کے لئے تشہد کے انداز میں بیٹھنے کا رواج ہے.ہندوستانی مسجد سے کی حالت کو انتہائی تذلل و
انکساری سمجھتا ہے.ایرانی کو ہاتھ چھوڑ کر کھڑا ہونے میں تذلیل محسوس ہوتا ہے.یہودی
کو رکوع میں
تذلل نظر آتا ہے.غرض جو قوم بھی اسلام میں داخل ہوتی ہے وہ نما ز میں اپنے ہاں کے مانوس طریق
ادب
و تعظیم کو دیکھ کہ اپنی روح کی تسکین اس میں بدرجہ اولی پاتی ہے.دیکھو یہ کتنی بڑی خوبی ہے جو اسلام
میں پائی جاتی ہے.باقی قوموں کی عبادتوں میں یہ چیز اتنے لطیف طریق پر نظر نہیں آتی اور یہ اس وجہ
سے ہے کہ اسلام ایک عالمگیر دین ہے اور ساری دنیا نے اس میں شامل ہوتا ہے.پھر اسلامی نماز میں ایک امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ فرض نماز سے پہلے وضو کے علاوہ کچھ نیتی اور نوافل کھردیئے
اور بعد میں بھی شستن نوافل او ذکر الہی کی تلقین فرمایا کہ خیال کو جمع کرنے اور دوسری چیزوں سے توجہ ہٹا کر خالصہ اللہ
تعالی کے لئے ہو جانے کا موقع انسان
کو میسر آتا ہے.یہ ایک نفسیاتی حقیقت ہے کہ ہر کام وقت سے
کچھ پہلے شروع کر دیا جاتا ہے مثلاً ہم نے دس بجے کی گاڑی پر جانا ہے تو آٹھ بجے سے ہی اس کا
خیال آنا شروع ہو جائے گا.ہم روزہ رکھے ہوئے ہیں تو سورج غروب ہونے سے پندرہ میں منٹ
پہلے ہی روزہ کھولنے کی تیاری شروع کر دیں گئے.یہی حال دوسرے کاموں کا ہے یعنی پہلے کام کا انتہ کچھ
دیر تک چلا جاتا ہے اور اگلا کام کچھ دیر پہلے شروع ہو جاتا ہے اس لحاظ سے اگر نماز سے پہلے وضو
اور بعد میں نوافل وغیرہ نہ رکھے جاتے تو آدھی نمانہ تو پہلے خیالات میں ضائع ہو جاتی اور آدھی دوسر
خیالات ہیں.اس نقص کے ازالہ کے لئے خدا تعالیٰ نے پہلے وضو رکھا اور فرائض سے پہلے سنتیں اور
Page 25
19
الله
نوافل رکھ دیئے اسی طرح فرائض کے بعد کچھ سنتیں اور نوافل رکھ لیے اس طرح نمازہ کو اس نے دو
دیواروں کے درمیان محفوظ کر لیا اور انسان کے لئے اس بات کا موقع بہم پہنچا دیا کہ وہ دنیوی خیالات
سے علیحدہ ہو کر نماز ادا کر سکے اور شیطانی حملوں سے ہر ممکن طریق سے محفوظ رہ سکے.پھر اسلام نے نماز کے لئے ایک قبلہ مقرر کیا ہے جس کی طرف ہر نماز پڑھنے والا منہ کرتا ہے مثلاً
افریقہ والے مشرق کی طرف منہ کرتے ہیں یورپ والے جنوب کی طرف منہ کرتے ہیں.ایران والے جنوب
مغرب کی طرف منہ کرتے ہیں.بر صغیر پاک و بھارت والے مغرب کی طرف منہ کرتے ہیں اور اس طرح ساری
دنیا کے مسلمانوں میں خواہ وہ شمال میں رہتے ہوں یا جنوب میں مشرق میں ہوں یا مغرب ہیں.یہ احساس
مستحکم ہو جاتا ہے کہ وہ ایک سمت کی طرف منہ کر کے کھڑے ہیں یہ ایک بہت بڑا اتحاد کا ذریعہ ہے
بشر طیکہ مسلمان اسے فائدہ اٹھائیں مگر اس کی ساتھ ہی اسلام نے یہ بھی کہدیا ہے کہ قبلہ اپنی ذات
میں کوئی خوبی نہیں رکھتا اور یہ اس لئے کہ تا شرک پیدا نہ ہو جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :-
وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ والمَغْرِبُ ، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ
للہ تعالی کے لئے مشرق اور مغرب سب برابر ہیں.جمعہ منہ کہ و اُدھر ہی تم اللہ تعالی گوپاو گے.غرض عبادت کو اس کماں تک اور کسی مذہب نے نہیں پہنچایا اور یہ اسلام کی فضیلت کا ایک بہت بڑا
ثبوت ہے.پھر اسلامی عبادت میں جماعت کا اصول قائم کیا گیا ہے جو مذہب کی اصل غرض ہے ظاہر ہے
که انسانی زندگی دو پہلووں پر مشتمل ہے.انفرادی اور اجتماعی - مذہب ، سیاست، قومیت، اخلاق -
تمدن تمام امور میں ان دونوں پہلوؤں کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے ورنہ انسانی سوسائٹی خراب
ہو جاتی ہے.جن اقوام نے سیاست میں اجتماعی زندگی اور اس کی ذمہ داریوں کا خیال نہیں رکھا وہ
کمزور ہو گئی ہیں.اسی طرح جن اقوام نے انسان کو محض مشین سیاست کا ایک پرزہ تجویز کر دیا ہے انہوں
نے بھی انسانی ترقی کے راستوں کو مسدود کر دیا ہے.اصل اور کامیاب طریقہ یہی ہے کہ انفرادیت اور
اجتماعیت دونوں کو ایک وقت میں اور تواندن کے ساتھ قائم رکھا جائے.مذہب میں بھی یہی طریقہ کامیاب
اور مفید ہو سکتا ہے.اسلام نے اس حکمت کو خاص طور پر مد نظر رکھا ہے اور مذہب میں اجتماعی رفرح
کو ایک مقرا در معزز مقام عطا کیا ہے مثلاً نماز ہے اس میں انفرادیت بھی ہے اور اجتماعیت بھی.لیکن اس میں جو جماعتی رنگ پایا جاتا ہے اُسے ایک خاص امتیاز حاصل ہے کیونکہ اسلام میں نمازہ
با جماعت کو واجب قرار دیدیا گیا ہے اور سوائے معذوروں کے اہمیں سب کا آنا ضروری سمجھا گیا ہے.ت: بقرہ : ۱۱۶
Page 26
۲۰
پھر اس کے ساتھ اسلام نے یہ ہدایت بھی دی ہے کہ اگر اپنے محلہ میں ہو تو اپنے محلہ کی مسجد میں نماز
پڑھنے کی کوشش کی جائے اسی دوسرے ہمسایوں سے تعلق اور یکسانیت اور اجتماعیت کی روح کو فروغ
حاصل ہوتا ہے.بغرض اس طرح سے اسلام نے جماعت میں جو فوائد ہو سکتے ہیں ان کو عمل کرنے کی کوشش کی ہے.روایات میں آتا ہے کہ ایک صحابی سے کسی نے کہا کہ چلو فلاں محلہ میں جا کر نماز پڑھیں اس صحابی نے کہا
یں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اپنے محلہ کی مسجد میں نماز ادا کرنی چاہیئے اس لئے میں
تو اپنے ہی محلہ کی مسجد میں نماز ادا کروں گا.پھر اسلامی نمازہ اتنے اوقات میں مقرر ہے کہ دوسرے مذاہب میں اس
کی کوئی مثال نہیں مل سکتی
ملا کر طلوع شمس سے پہلے نماز ہے (۲) زوال شمس کے بعد نماز ہے (۳) غروب شمس کے قریب نماز ہے
دم غروب آفتاب کے بعد نماز ہے (ہ) رات کو سونے سے پہلے نماز ہے اور یہ پانچ نمازیں فرض ہیں.یہ
نہیں کہ ان کی ادائیگی کسی کی مرضی پر منحصر ہو.اسقدر عبادت اور پھر با جماعت عبادت اوڑی میں کہاں پائی جاتی ہر ؟
خلاصہ یہ کہ اسلام نے نماز کے لئے مختلف اوقات کا جو اصل قائم کیا ہے اور جسکے ذریعہ اسلام
نے بکثرت قومی اجتماع کی صورت پیدا کی ہے.اس کی دنیا میں اوبر کہیں مثال نہیں ملتی.پس اس لحاظ سے نمازہ ایک ایسی عبادت ہے جو دوسر سے تمام مذاہب کی عبادتوں سے مختلف
ہے اس میں اجتماعیت اور انفرادیت دونوں کا لحاظ رکھا گیا ہے.نماز پڑھنے کے وقت مسلمان اللہ تعالیٰ کی
حمد اور اس کی نشاء کرتے ہیں اور اس کے حضور میں دعائیں کرتے ہیں اور اپنی اصلاح اور روحانی ترقی اور اپنے
دوستوں اور عزیزوں اور باقی سب دنیا کی جسمانی اور روحانی ترقی کے لئے اس کے سامنے درخواستیں پیش
کرتے ہیں ان کی اس سادہ نمازہ کی شان یہ ہوتی ہے کہ نماز کے وقت میں کوئی مومن او ہر ادہر نہیں دیکھ
ستان نماز میں کسی اور سے بات کر سکتا ہے مسجد میں نماز ادا کرتے وقت کسی قومی یا نسلی امتیاز کا لحاظ
نہیں رکھا جاتا.اللہ تعالیٰ کے حضور سب برابر ہیں.غریب اور امیر ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں.بادشاہ کے ساتھ اس کا خادم کھڑے ہونے کاحق رکھتا ہے اس کا کناس بھی اس کے ساتھ کھڑے ہونے کا
حق رکھتا ہے.نماز کے وقت میں ایک حج اور ایک مجرم - ایک جرنیل اور ایک سپاہی پہلو بہ پہلو کھڑے
ہوتے ہیں کوئی کسی کی طرف انگلی نہیں اُٹھا سکتا کوئی کسی کو اس کی جگہ سے پیچھے نہیں ہٹا سکتا مسجد میں
ہر ایک برابر کا حقدار ہے اور مساوی درجہ رکھتا ہے.پس تمام کے تمام ایک ہی درجہ میں خاموشی سے
خدا تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور امام کے اشارے پر رکوع اور سجود اور قیام کے احکام بجالاتے
ہیں بعض اوقات امام قرآن شریف کی آیتیں بلند آواز سے پڑھتا ہے تاکہ ساری جماعت ایک خاص نصیحت کو.
Page 27
اپنے سامنے لے آئے.نماز کے بعض حصوں میں ہر شخص اپنے اپنے طور پر مقررہ دعائیں اور وہ دعائیں
بھی جن کو وہ چاہتا ہے پڑھتا ہے لیے
پھر اسلام نے ایک اور حد بندی بھی توڑ دی ہے.عیسائی نے اگر نماز پڑھنی ہو تودہ گرجے میں جائیگا ہنڈ نے
گر نماز پڑھنی ہو تو مندرمیں جائیگا.سکھ نے اگرنماز پڑھی ہو وہ گوردوار میں جائیگا لیکن سول کریم صلی الہ علیہ سلم نے فرمایا.جُعِلَتْ لى الارض مسجداً له
میرے لئے ساری زمین مسجد بنادی گئی ہے عیسائیوں میں صرف گرجوں میں عبادت ہوتی ہے منڈوں میں صرف
مندروں میں عبادت ہوتی ہے مگر ساری زمین کے چپہ چپہ پر صرف مسلمانوں نے سجدہ کیا ہے.ہم جب پہاڑوں پر
جاتے ہیں تو جان بوجھ کر مختلف جگہوں پر نماز پڑھتے ہیں تاکہ کوئی جگہ ایسی نہ رہ جائے جہاں خدا تعالی کی عبادت
نہ کی گئی ہو.دیکھو کتنی وسعت ہے جو اسلام میں پائی جاتی ہے.جہاں خداتعالی نے امامت میں ہر ایک کو حقدار
یا کہ انسانوں میں مساوات قائم کر دی ہے وہاں جعلت لى الارض مسجداً لہکر زمین چہ چہ میں مساوات
قائم کردی.پھر ایک طرف جہاں جَعَلَتْ بي الارض مسجداً لیکر اتنی ساری زمین کو مسجد میں تبدیل کر دیا
وہاں فرائض کے ساتھ نوافل ملا کر اس نے ہر گھر کوسجد بنا دیاکیونکہ نوافل کے متعلق رسول کریم صلی الہ علی وسلم
نے یہ پسند فرمایا ہے کہ وہ گھر میں پڑھے جائیں جیسے فرمایا لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ اپنے گھروں
کو مقبرے نہ بناؤ یعنی جیسے مقابر پر نمازہ پڑھی جانہ نہیں اس طرح تم گھروں کو بھی مت کھو بلکہ کچھ نمازیں
گھر میں ادا کیا کرو.اس طرح خدا تعالیٰ نے زمین کے چپہ چپہ پر عبادت کے لئے راستہ کھول دیا.اسلامی نمانہ کو الہ تعالیٰ نے اپنے تقاء کا ایک ذریعہ بنایا ہے اللہ اکبر کہہ دینے کے بعد نماز پڑھنے
والے گویا خدا تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو جاتے ہیں بلکہ وہ کلی طور پر عبادت میں محو ہو جاتے ہیں وہ کسی سے
بات نہیں کر سکتے دوسرے کے سلام کا جواب بھی نہیں دے سکتے حتی کہ باہر والے کا بھی حق نہیں ہوتا کہ
وہ نماندی کی غلطی پر اس کو توجہ دلائے مثلاً کوئی نمازی ایک سجدہ زیادہ کر ویسے یا کم کرد سے تو ایک ایسا آدمی
جو نماز میں شامل نہیں اُسے اس غلطی پر آگاہ نہیں کر سکتا.گویا ایک مسلمان جب نماز پڑھتا ہے تو وہ
خداتعالی کے دربار میںحاضر ہو جاتا ہے اور کسی باہر والے کا یہ حق نہیں رہتا کہ وہ اسی کام میں دخل دے.ہاں و شخص غلطی نکال سکتا ہے جو اس کے ساتھ جماعت میں شامل ہو.اسی طرح وہ ادہر ادہر جھانک بھی نہیں
سکتا.رسول کریم صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا.جو نمازی ادہر ادھر دیکھے گا خدا تعالیٰ اس کا سر گدھے اس بنا دیگا.اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انسان کی حماقت کی طرف اشارہ کیا ہے اور اس میں کیا شبہ
ہے کہ ایسا شخص اول درجہ کا احمق ہوتا ہے وہ نماز میں ادہر ادہر کیوں دیکھتا ہے اسی لئے کہ اُسے کوئی
ے دیباچہ تفسیر القرآن : : بخاری کتاب القیم کے :- ترمذی باب ثواب القرآن :
Page 28
عجیب چیز نظر آتی ہے مگر سوال یہ ہے کہ خُدا تعالیٰ جیسی عجیب چیز اور کونسی ہے اور اگر وہ خدا تعالیٰ کو چھوڑ
کر اور چیزوں کو دیکھتا ہے تو وہ یقینا گدھا ہے اسکی سامنے خدا تعالیٰ جیسا حسین چہرہ ہے اور وہ دیکھ
رہا ہے بلی یا چوہے کو.تو اس کے گدھا ہونے میں کیا شک ہے.غرض نمازمیں کلی طور پر انقطاع الی اللہ ہوتا ہے اور نماز شروع کرتے وقت اللہ اکبر کہنے میں ہی حکمت
ہے گویا تکبیر کہنے والا یہ اعلان کرتا ہے.اسے میرے بھائیو اور اسے میرے عزیز وا در رشته وارد باتم بھی مجھے
عزیز ہومگر تم سے زیادہ مجھے خداتعالی عزیز ہے وہ سرسے بڑا ہے میں اس
کے سامنے جاتا ہوں اور تم سے قطع
تعلق کرتا ہوں.جب نماز ختم ہوتی ہے تو وہ السلام علیکم ورحمہ اللہ کہتا ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں اب
واپس آگیا ہوں جیسے کوئی باہر سے آنے سے السلام علیکم کہتا ہے اسی طرح وہ بھی کہتا ہے میں باہر گیا ہوا تھا
اب واپس آگیا ہوں.یکتنی خالص اور شکیل نمانہ ہے.اقامة الصلواة
اقامت کے معنے نماز پڑھنے کے لئے قرآن کریم نے اقامت الصلوۃ کے الفاظ استعمال کئے
ہیں.اقامت کے ایک منے کسی بات پر قائم اور تجھے رہنے کے ہیں اس لحاظ
سے اقامت الصلواۃ کے معنے یہ ہوں گے کہ بلاناغہ باقاعدگی سے نما نہ ادا کی جائے اس میں غفلت اور
راپر واہی سے کام نہ لیا جائے کیونکہ نمانہ وہی ہے جو باقاعدگی سے پڑھی جائے.اقامت کے دوسرے معنے اعتدال اور درستی کے ہیں یعنی نمازہ ٹھیک ٹھیک پوری شرائط کو
ملحوظ رکھکر بر وقت ادا کی جائے کسی شرط یا رکن کو چھوڑنا نماز کو ضائع کرنے کے مترادف ہے.اقامت کے تیسرے معنے کسی چیز کو رواج دینے اور اسے عام کرنے کے ہیں.اس لحاظ سے قامتہ الفصل
کے یہ معنے ہوں گے کہ نماز نہ صرف خود پڑھی جائے بلکہ دوسروں میں بھی اس کو رواج دیا جائے اور ترغیب
دلائی جائے کہ لوگ باقاعدگی سے نماز پڑھیں.گویا للہ تعالٰی مومنوں سے یہ توقع رکھتا ہے کہ وہ لوگوں میں نماز قائم کریں.انہیں نماز پڑھنے کی تحریک
کریں.اگر انہیں نماز پڑھنی نہیں آتی تو انہیں نماز پڑھنا سکھائیں اگر کوئی شخص نماز کا ترجمہ نہیں جانتا تو
اُسے نمازہ کا ترجمہ پڑھائیں.غرض ہر
شخص نماز کی ترویج اور اس کو دنیا میں قائم کرنے میں مشغول ہو جائے.کوئی شخص نماز کی خوبیاں بیان
کر رہا ہو.کوئی نما کا ترجمہ پڑھا رہا ہو.کوئی شخص نمازیں ادا کر نے کیلئے لوگوں کو
تحریک کر رہا ہو.کوئی شخص نما نہ پڑھنے والوں میں نماند کی مزید رغبت پیدا کر رہا ہو.اس طرح کوئی مومن
Page 29
۲۳
ایسا نہ ہو جو یقیمون الصلوۃ کے حکم پر عمل نہ کر رہا ہو.پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارا صرف یہی کام نہیں
خود نمازیں پڑھو کہ ہمارا یہ بھی کام ہے کہ تم لگوں کونمانہ کی تحریک کر کے ان پڑھوں کو نماز کا ترجمہ کھا کے
اور نماز پڑھنے والوں کونماز کی مزید رغبت دل کے دنیا یں پوری مضبوطی کیساتھ نمازوں کا رواج قائم کر دولہ
اقامت الصلوۃ کے چوتھے معنے یہ ہیں کہ نماز با جماعت ادا کی جائے.نماز با جماعت شروع ہونے سے
پہلے جو اقامت کہی جاتی ہے اس میں انہی معنوں کی طرف اشارہ ہے گویا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارا صرف یہی
فرض نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت
کرو بلکہ یہ بھی فرض ہے کہ تم جماعت کے ساتھ نماز پڑھو مطلب یہ کہ ہم
تمہیں صرف عبادت
کا حکم نہیں دیتے بلکہ باجماعت عبادت کا حکم دیتے ہیں.اور اس کی وجہ یہ ہے کہ
اسلام فردی مذہب نہیں بلکہ قومی مذہب ہے.باقی سارے مذاہب میں اگر افراد الگ الگ عبادت
کرتے ہیں تو وہ بڑے زاہد ، بڑے عابد ، بڑے پر ہیز گار اور بیڑ سے عارف سمجھے جاتے ہیں کہ یہ لوگ
ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس کا وصال حاصل ہے مگر اسلام کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص یا جماعت
نماز ادا نہیں کرتا تو خواہ وہ علیحدگی میں کتنی عبادتیں کرتا ہو وہ ہر گز نیک اور پارسا نہیں سمجھا جا سکتا
اور اسے ہرگز قوم میں عزت کا مقام نہیں دیا جا سکتا.یہ ایک بہت بڑا فرق ہے جو اسلام اور
غیر مذاہب میں پایا جاتا ہے.پس وہ لوگ جن کو دوسری قومیں محض علیحدگی میں عبادت کرنے کی وجہ سے بزرگ قرار دیتی ہیں.اسلام ان کو مرتد و مردود قرار دیتا ہے.دنیا ان کو خدا رسیدہ سمجھتی ہے اور اسلام ان کو اللہ تعالی کے
قریبے راندہ ہو سمجھتا ہے کیونکہ اسلام کہتا ہے اقیموا الصلوۃ ہم نے تمہیں صرف اتنا حکم نہیں دیا کہ
تم نمازیں پڑھو بلکہ ہمارا حکم یہ ہے کہ تم لوگوں کےساتھ مل کر نمازیں پڑھو اور اپنی ہی حالت کو درست نہ
کرو بلکہ ساری قوم کو سہارا دیکر اس کی روحانیت کو بلند کرو اور قوم سے دور نہ بھا گو بلکہ اس کے ساتھ
رہو اور ہوشیار چوکیدار کی طرح اس کے اخلاق اور روحانیت کا پہرہ دو سے
اقامت کے پانچویں معنے کسی چیز کو جو گرا چاہتی ہے کھڑا رکھنے اور اسے گرنے نہ دینے کے ہیں یعنی
نماز کو قائم رکھنے کی کوشش میں لگا رہنا چاہیئے اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ انسان یکساں حالت
میں نہیں رہتا.بعض اوقات وہ نماز میں پریشان خیالی سے بھی دوچار ہو سکتا ہے لیکن اسے اسے
یا یوسی نہیں ہونا چاہیئے اور نہ ہی اپنی نمازہ کو بے کار سمجھنا چاہیئے بلکہ درست طریق پر ادا کرنیکی کوشش
میں لگا رہنا چاہیئے کیونکہ الہ تعالیٰ بندوں سے اسی قدر قربانی کی امید کرتا ہے جتنی قربانی ان کے بس
میں ہو.پس ایسے نمازی جن کے خیالات پراگندہ ہو جاتے ہیں اور نماز میں اپنی توجہ قائم نہیں رکھ
تغیر کبیر جلد شتم زد چهارم و ان سے تفسیر کبیر جلد ششم جز و چهارم حصہ دوم ۳
و
Page 30
۲۴
سکتے.اگر وہ اپنی نماز کو سنوار کمر اور توجہ سے پڑھنے کی کوشش میں لگے رہیں تو چونکہ وہ اپنی نماز کو
جب بھی وہ اپنے مقام سے گر سے کھڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسلئے اللہ تعالیٰ ان کی نمازہ کو ضائع
نہیں کرے گا اور اُسے بے نتیجہ نہیں رہنے دے گا.حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں :-
و متقی خدا تعالیٰ سے ڈرا کرتا ہے اور وہ نماز کو قائم کرتا ہے اس حالت میں مختلف قسم
کے وساوس اور خطرات بھی ہوتے ہیں جو پیدا ہو کر اسکی حضور میں حارج ہوتے ہیں اور نماز کو
گرا دیتے ہیں لیکن یہ نفس کی اس کشاکش میں بھی نماز کو کھڑا کرتا ہے کبھی نمانہ گرتی ہے.مگر
یہ پھر اُسے کھڑا کرتا ہے اور یہی حالت اس کی رہتی ہے کہ وہ تکلف اور کوشش سے بار بار
اپنی نماز کو کھڑا کرتا ہے یہاں تک
کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس کلام کے ذریعہ ہدایت عطا کرتا ہے
اس کی ہدایت
کیا ہوتی ہے ؟ اس وقت بجائے یقیمون الصلوۃ کے ان کی یہ حالت ہو جاتی
ہے کہ وہ اس کشمکش اور وساوس کی زندگی سے نکل جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ غیب کے ذریعہ
سے انہیں وہ مقام عطا کرتا ہے جس کی نسبت فرمایا ہے کہ بعض آدمی ایسے کامل ہو جاتے
ہیں کہ نماز ان کے لئے بمنزلہ غذا ہو جاتی ہے اور نماز میں ان کو وہ لذت اور ذوق عطا کیا جاتا
ہے جیسے سخت پیاس کے وقت ٹھنڈا پانی پینے سے حاصل ہوتا ہے کیونکہ وہ نہایت رغبت
سے اُسے پیتا ہے اور خوب سیر ہو کر خط حاصل کرتا ہے یا سخت بھوک کی حالت ہو اور اُسے
نہایت ہی اعلیٰ درجہ کا خوش ذائقہ کھانامل جاد سے جس کو کھا کہ وہ بہت ہی خوش ہوتا ہے
یہی حالت نماز میں ہو جاتی ہے اور وہ نماز اس کے لئے ایک قسم کا نشہ ہو جاتی ہے جس کے
بغیر وہ سخت کرب اور اضطراب محسوس کرتا ہے لیکن نمازنہ کے ادا کرنے سے اسکی دل میں ایک
خاص سرور اور ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے جس کو ہر
شخص نہیں پا سکتا اور نہ الفاظ میں یہ لذت
بیان ہو سکتی ہے اور انسان ترقی کر کے ایسی حالت میں پہنچ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اُسے
ذاتی محبت ہو جاتی ہے اور اس کو نماز کے کھڑا کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی اس لئے کہ وہ
نما نہ اس کی کھڑی ہی ہوتی ہے اور ہر وقت کھڑی ہی رہتی ہے اس میں ایک طبعی حالت پیدا
ہو جاتی ہے اور ایسے انسان کی مرضی خدا تعالیٰ کی مرضی کے موافق ہوتی ہے انسان پر ایسی حالت
آتی ہے کہ اس
کی محبت اللہ تعالیٰ سے محبت ذاتی کا رنگ دیکھتی ہے اس میں کوئی تکلف اور بناوٹ
نہیں ہوتی جس طرح پر حیوانات اور دوسرے انسان اپنے ماکولات اور مشروبات اور دوسری
شہوات میں لذت اُٹھاتے ہیں اسی بہت بڑھ چڑھ کر وہ مومن متقی نمازہ میں لذت پاتا ہے.
Page 31
نماز ساری ترقیوں کی جڑ اور زینہ ہے اسی لئے کہا گیا ہے کہ نماز مومن کا معراج ہے اس دنیا میں ہزاروں
لاکھوں اولیاء اللہ، راستباز، ابدال، قطب گزرے ہیں انہوں نے یہ مدارج اور مراتب کیونکر حاصل
کئے ؟ اسی زمانہ کے ذریعہ سے خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرة عيني في الصلاة یعنی
میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے اور فی الحقیقت جب انسان اس مقام اور درجہ پر پہنچتا ہے
تو اس کے لئے اکمل اسم لذت نمازہ ہی ہوتی ہے اور یہی معنے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد
کے ہیں پیس کشاکش نفس سے انسان نجات پا کر اعلیٰ مقام یہ پہنچ جاتا ہے.غرض یاد رکھو کہ یقیمون الصلوۃ وہ ابتدائی درجہ اور مرحلہ ہے جہاں نماز ہے ذوقی اور
کشاکشی سے ادا کرتا ہے لیکن اس کتاب یعنی قرآن کریم کی ہدایت ایسے آدمی کے لئے یہ ہے کہ اس مرحلہ
سے نجات پا کر اس مقام پر جاپہنچتا ہے جہاں نماز اس کے لئے قرۃ العین ہو جاو سے" سے
صلواۃ کے معنے حرکت کرنے اور کو ہلے کو ہلانے کے ہیں اس لحاظ سے نماز کو صلواۃ
اس لئے کہا گیا ہے کہ نمازہ بھی انسان کو مستعد اور فرض شناسی بناتی ہے شکست
صلواۃ کے مع
اور بے کار بیٹھنے نہیں دیتی.نماز پڑھنے والا انسان اللہ تعالٰی اور اس کے بندوں کے حقوق ادا کرنے
ہمیشہ مستعد اور تیار رہتا ہے کسل مندی اور سستی سے اُسے نفرت پیدا ہو جاتی ہے.صلوة صَلَّی سے ہے اس کے معنے جلنے اور بھوننے کے ہیں ان معنوں کے لحاظ سے نماز کو
صلوۃ اس لئے کہتے ہیں کہ اس کے ذریعہ محبت الہی کو حرارت حاصل ہوتی ہے بلکہ صوفیاء نے تو کہا
ہے کہ جس طرح کباب
بھونا جاتا ہے اسی طرح نماز میں بھی سوزش محبت لازم ہے جب تک دل
بریاں نہ ہو نماز میں لذت اور سرور پیدا نہیں ہوتا.صلوۃ کے ایک معنے والہانہ دعا اور پکار کے ہیں اور نماز کا مغز اور اس کی روح بھی دعا
ہے یعنی نماز میں انسان اللہ تعالیٰ کی محبت کا سوالی بن کر اس کے دربار میں جاتا ہے اس لئے نمازہ
کو صلوۃ یعنی دعائے مجسم کہا گیا ہے یا چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ اسلام فرماتے ہیں.ایک مری میں خیال کیا ک صلوات میں اوردعائیں کیافرق مرود میں آیا ہے کہ الصَّلوةُ فِى الدُّعَا الصَّلوة
من العِبَادَةِ یعنی نماز ہی دعا ہے.نماز عبادت کا مغز ہے.جب انسان کی دُعا
محض دنیوی امور کے لئے ہو تو اس کا نام صلواۃ نہیں لیکن جب انسان خدا کو ملنا چاہتا
ہے اور اس کی رضا کو مد نظر رکھتا ہے اور ادب ، انکسار ، تواضع اور نہایت محویت
کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور میں کھڑا ہو کر اس کی رضا کا طالب ہوتا ہے تب وہ صلوٰۃ
ے :.نسائی باب النساء : 1 سه :- ملفوظات جلد ہشتم ۳۰-۳۱۰ ۳: المفردات زیر لفظ صلا
Page 32
۲۶
میں ہوتا ہے.اصل حقیقت دعا کی وہ ہے جسکسی ذریعہ سے خُدا اور انسان کے درمیان
رابطہ تعلق بڑھے.یہی دُعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر نے کا ذریعہ ہوتی ہے اور انسان
کو نا معقول باتوں سے ہٹاتی ہے اصل بات یہی ہے کہ انسان رضائے الہی کو حاصل کر سے
اسکی بعد روا ہے کہ انسان اپنی دنیوی ضروریات کے واسطے بھی دعا کہ سے یہ اس واسطے
روا رکھا گیا ہے کہ دنیوی مشکلات بعض دفعہ دینی معاملات میں خارج ہو جاتے ہیں یا مکہ
خامی اور کنج پینے کے زمانہ میں یہ امور ٹھوکر کا موجب بن جاتے ہیں.صلوۃ کا لفظ پرسوز
معنے پر دلالت کرتا ہے جیسے آگ سے سوزش پیدا ہوتی ہے ویسی ہی گدازش دعا میں پیدا
ہونی چاہیئے.جب ایسی حالت کو پہنچ جائے جیسے موت کی حالت ہے تب اس کا نام
صلوۃ ہے.نماز اور دُعا نمازہ کے ذریعہ اسلام نے دنیا کا راستہ کھولا ہے.دعا نماز کا اہم حصہ ہے کیونکہ
دعا
دعا ہی
کے ذریعہ دنیا کی کل حکمتیں ظاہر ہوتی ہیں ہر ایک بیت العلم کی کبھی دعا
ہے اور کوئی علم و معرفت کا دقیقہ نہیں جو بغیر اس کی ظہور میں آیا ہو.دُعا کیا ہے ؟ جب ہم فکر و غور
کے وقت ایک مخفی امر کی تلاش میں نہایت عمیق دریا میں اتر کر ہا تھ پاؤں مارتے ہیں تو ہم اس
حالت میں بنزبان حال اس اعلی طاقت سے فیض طلب کر تے ہیں جسے کوئی چیز پوشیدہ نہیں
اس طلب فیضان کا دوسرا نام دُعا ہے.جب ہماری روح ایک چیز کی طلب میں بڑی سرگرمی اور سوز و گداز کے ساتھ مبداء فیض کی طرف
ہاتھ پھیلاتی ہے اور اپنے تئیں عاجزہ پا کر فکر کے ذریعہ کسی اور جگہ روشنی ڈھونڈتی ہے تو درحقیقت وہ دُعا
سے ہی کام سے رہی ہوتی ہے.دعا کرنے سے کیا مطلب ہوتا ہے ؟ یہی کہ عالم الغیب جس کو دقیق د
دقیق تدبیریں معلوم ہیں کوئی احسن تدبیر دل میں ڈال دے یا بوجہ خالقیت اور قدرت اپنی طرف سے
پیدا کر سے.پس ثابت ہوا کہ دُعا در حقیقت تلاش تدبیر کا نام ہے.در
دیما اور تدابیر انسانی طبیعت کے دو طبیعی تقاضے ہیں جو قدیم سے اور جیسے کہ انسان
پیدا ہوا ہے دو حقیقی بھائیوں کی طرح انسانی فطرت کے خادم چلے آئے ہیں.انسانی طبائع کسی
مصیبت کے وقت جس طرح تدابیر اور علاج کی طرف مشغول ہوئی ہیں ایسا ہی طبعی جوش سے دُعا
صدقہ اور خیرات کی طرف مجھک جاتی ہیں.اگر دنیا کی تمام قوموں پر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ
اب تک کسی قوم کا کانشنس اس متفق علیہ مسئلہ کے برخلاف ظاہر نہیں ہوا پس یہ ایک روحانی
ه : ملفوظات جلد هفتم من :
Page 33
۲۷
دلیل اس بات پر ہے کہ انسان کی شریعت باطنی نے قدیم سے تمام قوموں کو یہی فتوی دیا ہے کہ
دہ دعا کو اسباب اور تدابیر سے الگ نہ کریں کیونکہ دعا تدبیر کے لئے بطور محرک اور جاذب کے ہے اور
تدبیر دکھا کے لئے بطور ایک نتیجہ ضرور یہ کے ہے پس دُعا سے اصل مطلب تدبیر کا پانا.اطمینان قہستی اور
حقیقی خوشحالی کا حاصل کرنا ہے اور جو شخص روح کی سچائی ہے دُعا کرتا ہے ممکن نہیں کہ حقیقی طور پر وہ نامراد
رہ سکے.البتہ یہ اللہتعالیٰ جانتا ہے کہ ایک دعا کر نے والے شخص کی حقیقی خوشحالی کس امر میں ہے.یہ چیز
خدا تعالی کے ہاتھ میں ہے جس پیرا یہ میں چاہے وہ عنایت فرمائے.اگر ہم اس خطا کار بچہ کی طرح جو
اپنی ماں سے سانپ یا آگ کا ٹکڑا مانگتا ہے اپنی دعا اور طلب میں غلطی پر ہوں تو خدا تعالیٰ وہ چیز جو
ہمارے لئے بہتر ہو خطا کرتا ہے اور اگر ہم اپنے مقصد کی طلب میں غلطی پر نہ ہوں تو وہی مقصد یہ آتا
ہے اور بایں ہمہ دونوں صورتوں میں ہمارے ایمان کو بھی وہ ترقی دیتا ہے کیونکہ دعا اور استجابت میں ایک
رشتہ ہے کہ ابتداء سے اور جب سے انسان پیدا ہوا ہے برابر چلا آتا ہے.جب خدا تعالی کا ارادہ
کسی بات کے کرنے کا ہوتا ہے تو سنت اللہ یہ ہے کہ اس کا کوئی مخلص بنده اضطراب اور کرب اور
قلق کے ساتھ دُعا کرنے میں مشغول ہو جاتا ہے اور اپنی تمام توجہ اس امر کے ہو جانے کے لئے کرتا
ہے تب اس مرد فانی کی دعائیں فیض الہی کو آسمان سے کھینچتی ہیں اور خدا تعالیٰ ایسے نئے اسباب
پیدا کر دیتا ہے جن سے کام بن جاتا ہے.ایسی دعا کہنے والوں کے لئے آسمان زمین کے نزدیک
آجاتا ہے اور دعا قبول ہو کہ مشکل کشائی کے لئے نئے اسباب پیدا کئے جاتے ہیں اور ان کا علم پیش
انہ وقت دیا جاتا ہے اور کم از کم یہ کہ مہینے آہنی کی طرح قبولیت دعا کا یقین غیب سے دل میں بیٹھ
جاتا ہے.سچ یہی ہے کہ اگر دُعا نہ ہوتی تو کوئی انسان خدا شناسی کے بارہ میں حق الیقین تک نہ
پہنچ سکتا.حقیقت یہی ہے کہ کوئی انسان بغیر ان قدرتی نشانوں کے ظاہر ہونے کے جو دُعا
کے بعد ظاہر ہوتے ہیں اس سچے ذوالجلال خدا کو پاہی نہیں سکتا.ہر ایک یقین کا بھوکا اور
پیاسا یاد رکھے کہ اس زندگی میں روحانی روشنی کے طالب کے لئے صرف دُعا ہی ایک ذریعہ ہے
جو خداتعالی کی ہستی پر یقین بخشتا ہے اور تمام شکوک و شبہات دور کر دیتا ہے.ہر ایک دعا اگر چہ
وہ ہماری دنیوی مشکل کشائی کے لئے ہو مگر وہ ہماری ایمانی حالت اور عرفانی تربیت پر گزر کر آتی
ہے.یعنی اول ہمیں ایمان اور عرفان میں ترقی بخشتی ہے اور ایک پاک سکینت اور انشراح مداوم
اطمینان عطا کرتی ہے پھر ہماری دنیوی مکروہات پر اپنا اثر ڈالتی ہے اور جس پہلو سے مناسب ہے
اس پہلو سے ہمارے غم کو دور کر دیتی ہے.پس دعا اس حالت میں دعا کہلا سکتی ہے کہ جب در حقیقت
Page 34
اس میں ایک قوت کشش ہو اور واقعی طور پر دعا کرنے کے بعد آسمان سے ایک نور انرز سے جو ہماری گھبراہٹ
کو دور کرے اور ہمیں انشراح بجتے اور سکینت اور اطمینان عطا کہ سے بیچی دکھا کے بعد خُدائے حکیم دو طور پر نصرت
اور امداد کو نازل کرتا ہے.ایک یہ کہ اس بلا کو دور کر دیتا ہے جسے نیچے دب
کر ہم مرنے کو تیار ہیں.دوسرے یہ کہ
بلا کی برداشت کیلئے ہمیں نہ صرف فوق العادت قوت عنایت کرتا ہے بلکہ اس میں نصرت اور انشراح بخشتا ہے "
نماز میں بے ذوقی کا علاج بھی دعا ہے اس سے آخر کا ر ذوق پیدا ہو جائیگا دعائیں دو قسم کی ہوتی ہیں مقررہ
اور مرخصہ مقررہ دعاؤں سے مراد اعلی درجہ کی اہم دعائیں ہیں جن کو ممکن تھا ہم دعا کرتے وقت چھوڑ دیتے.یا
وہ ہمارے ذہن میں نہ آئیں سو وہ اللہ تعالیٰ اور اسکے رسول نے قرآن و حدیث میں خود مقرر کر دیں مثلاً الحمد للہ
سے ضالین تک جو دنیا ہے وہ ہمارے ذہن میں نہ آسکتی تھی یا سمع اللہ لمن حمد ربنا لک الحمد و غیره کلمات
ہیں یہ سب ہمارے وہم وگمان میں بھی نہیں آسکتے تھے سو ان کو خُدا اور اس کے رسول نے خود مقرر کر دیا.مرخصہ وہ دعائیں ہیں جو ہم اپنی ضرورتوں کے لئے اپنی زبان میں کر سکتے ہیں مثلاً اگر ہمارا مالی نقصان ہو جائے
لازمت میں خرابی واقعہ ہو جائے تجارت میں ترقی نہ ہو یا کوئی اور ضرورت درپیش ہو تو اس کے لئے اپنی زبان
میں اور اپنی ضروریات کے مطابق دعائیں مانگنے کی اجازت ہے.نماز میں ذکر ودھا کی ہدایت فرما کہ اللہ تعالٰی نے صفا الہیہ پر غور کر نیکا راستہ کھول دیا ہے مسلمان
اپنی نمازہ میں روزانہ قرآن کریم پڑھتا ہے دعائیں کرتا ہے، رکوع و سجود میں دعائیں کرتا ہے سورۃ فاتحہ کے
کلمات طیبات رب العالمين الرحمن الرحیم.مالک یوم الدین - ایاک نعبد و ایاک نستعین اس کے سامنے آتے
رہتے ہیں اور وہ اُن پر غور کرتا ہے.غرض اسلام نے ہر سمان کو حکم دیا کہ وہ یہ دعا خود پڑھے اور غور و فکر سے پڑھے.پس اس طرح سے
اس نے ہر ایک کے لئے صفات الہیہ پر خور دن کہ کا راستہ کھول دیا ہے.قبولیت دعا کی عظمت پر ایک فلیے شہادت حضرت مسیح موعود علیہ اسلام فرما تے ہیں." وہ جو عرب کے بیابان ملک میں
ایک عجیب ماجرا گذرا کہ لاکھوں مرد سے تھوڑے دنوں میں زندہ ہو گئے اور رشتوں کے بگڑے
ہوئے الہی رنگ پڑ گئے اور آنکھوں
کے اندھے بینا ہوئے اور گونگوں کی زبان پر اپنی معارف جاری
ہوگئے اور دنیا میں ایک دفعہ ایک ایسا انقلاب پیدا ہوا کہ نہ پہلے اسے کسی آنکھ نے دیکھا اور
نہ کسی کان نے سنا.کچھ جانتے ہو کہ وہ کیا تھا.وہ ایک فانی فی اللہ کی اندھیری راتوں کی دعائیں ہیں
تھیں جنہوں نے دنیا میں شور مچا دیا اور وہ عجائب باتیں دکھلائیں کہ جو اس اُمتی ہے کسی سے
له: بركات الدعا ملخصا -
:
Page 35
۲۹
محالات کی طرح نظر آتی تھیں.اللهم صل وسلم وبارك عليه واله بعد دهمه وغمه
وحزنه لهذه الامة وانزل عليه انوار رحمتك الى الابد - له
نماز اور ذکر الہی نماز کی اپنی کا جمعہ ہے اور ا تعالی کا ذکر ایسی چیز ہے جو قلوب و اطمینان
عطا کرتا ہے جیسا کہ فرمایا الا بذکر الله تطمئن القلوب.پس جہاں
تک ممکن ہو نمازہ میں ذکر الہی کیا جائے اسی اطمینان حاصل ہو گا ہاں اس کے واسطے صبر اور محنت درکار
ہے.اگر انسان گھبرا جاتا ہے اور تھک جاتا ہے تو پھر یہ اطمینان نصیب نہیں ہو سکتا.دیکھو ایک کسان
کس طرح پر محنت کرتا ہے اور پھر کسی صبر اور حوصلہ کے ساتھ باہر اتنا غلہ کھیر آتا ہے بظاہر دیکھتے
والے یہی کہتے ہیں کہ انھی دانے ضائع کر دیئے لیکن ایک قت آجاتا ہے کہ وہ ان بکھر سے دانوں
سے ایک خرمن جمع کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ پر حسن ظن رکھتا ہے اور صبر کرتا ہے.اسی طرح مومن
جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق پیدا کر کے اس کی یاد میں استقامت اور صبر کا نمونہ
دکھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل وکرم سے اس پر مہربانی کرتا ہے اور اُسے وہ ذوق و
شوق اور علم و معرفت عطا کرتا ہے جس کا وہ طالب ہوتا ہے یہ بڑی غلطی ہے کہ جو لوگ کوشش
اور سعی تو کرتے نہیں اور پھر چاہتے ہیں کہ ہمیں ذوق و شوق اور علم و معرفت اور سکینت و اطمینان
قلب حاصل ہو جبکہ دنیوی اور سفلی امور کے لئے محنت اور صبر کی ضرورت ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو پھونک
مار کر وہ کیسے پا سکتے ہیں.یہیں خُدایا نی اور خُدا شناسی کے لئے ضروری امر یہی ہے کہ انسان عاؤں
میں لگا رہے.زمانہ حالت اور بزدلی سے کچھ نہیں ہو گا.اس راہ میں مردانہ والہ قدم اٹھانا چاہیئے
اور ہر قسم کی تکلیفوں کو برداشت کرنے کے لئے تیار رہنا چاہیے.خدا تعالیٰ کو مقدم کرلے اور گھیرائے
نہیں.پھر امید کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل دستگیری کرے گا اور اطمینان عطا فرمائے گا.ذکر کا عام تعلق غیر معین عبادت سے ہے.یہ عبادت غیر معین صورت میں اس لئے رکھی کہ معین
صورت کی نماز تو ہر وقت ادا نہیں ہو سکتی لیکن غیر معین صورت کی نماز یعنی عبادت ہر وقت ادا کی
جاسکتی ہے.سوتے جاگتے.چلتے پھرتے ہر حالت میں ذکر ہو جاتا ہے کیسی شخص نے ایک بزرگ سے
پوچھا کہ اگر ہم عبادت ہی کرتے رہیں تو ہم کام کیسے کریں ؟ انہوں نے فرمایا دوست در کار دل بایار
اپنے کاموں
کو بھی کرتے جاؤ اور ذکر الہی بھی کرتے رہو.پیشے کرو ، تجارتیں کرو.دوسرے دنیوی
کاروبار غرض ہر پیشے والا قبیح کو بھی جاری رکھ سکتا ہے اور اپنا کام بھی کر سکتا ہے لیکن نمازیں
ہر وقت نہیں پڑھی جاسکتیں ہم کھڑے ہوں تب بھی سبحان اللہ کہ سکتے ہیں.تیر رہے ہوں تب بھی
بركات الدعاما - روحانی خزائن جلد 4 : :- الرعد : ۲۹ :
Page 36
شان اللہ کر سکتے ہیں.ہندو کشادہ کر رہے ہوں تب بھی شبانالہ کہ سکتے ہیں موٹر چلا رہے ہو تب بھی امان اللہ کہ سکتے
ہیں مگر اس قسم کا ذکرہ اسلام کے علاوہ اور کس مذہب میں نہیں.ہند کو کہو کہ وہ اپنی کتاب سے نکالے.زردشتی کو
کہو کہ وہ اپنی کتاب سے نکالے.اس قسم کے ذکر کا دوسر ے مذاہب میں کہیں نام ونشان بھی
نہیں ملے گا.غرض خدا تعالٰی نے اس طرح عبادت کے راستے کھول دئے ہیں کہ اگر کوئی دیانتدار
ہو تو وہ مجبور ہے کہ ذکر الہی کہ ہے.(1)
سب سے بڑا ذکر تو بسم اللہ ہے رسول کریم صل اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جب کوئی کام کرو تو اس کے
شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کرو بسم اللہ کے بغیروہ کام بے برکت ہو جائے گا انسان کپڑے
پہنے تو بس اللہ کہے.جوتی پہنے توسیم اللہ کہے.پانی پئے تو ہم اللہ کہے، برتن مانجے تو ظیم اللہ کہے.جانور ذبح کرے تو بسم اللہ کہے.گوشت پکائے تو بسم اللہ کہے.غرض ہر کام شروع کرنے سے پہلے
بسم اللہ کہے.بسم اللہ میں اس طرف اشارہ ہوتا ہے کہ دنیا میں جس قدر چیزیں پائی جاتی ہیں یہ سب کی
سب
اللہ تعالیٰ کی ملک ہیں اور میں اس کی اجازت کے ماتحت ان کو اپنے استعمال میں لا رہا ہوں.مشداً جانور ذبح کرتے وقت جب وہ بسم اللہ کہتا ہے تو اس کے معنے یہ ہوتے ہیں کہ یہ جانور میں نے کہ
سے چھینا نہیں اللہ تعالٰی اس کا مالک ہے اس نے مجھے کہا ہے کھا لو اس لئے میں اسے ذبح کرتا ہوں
پھر مریح ہے وہ بھی خدا تعالیٰ کی دی ہوئی ہے کوئلہ ہے وہ بھی خدا تعالیٰ کا دیا ہوا ہے برتن ہیں وہ بھی خدا تعالیٰ
کے دیئے ہوئے ہیں میں تو مستعار طور پر اس کی مسکیتی چیزوں سے فائدہ اُٹھا رہا ہوں.(۲)
وسرا کہ الحمد لہ ہے جو کام کے ختم ہونے پر کیاجاتا ہے.قرآن کریم بی بی ارتقای فرماتا ہے.واخر دعوهم ان الحمد لله رب العالمیں مومنوں کا آخری قول یہی ہوتا ہے کہ
تعریفیں اُس خُدا کے لئے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے.۸۳)
تیسراذکر سُبحان اللہ ہے جو ہر تعجب انگیز اور بڑے کام پر کہا جاتا ہے اگر اس پربھی غورکیا جائے
تو یہ ذکرا اپنے اندر بڑی حکمتیں رکھتا ہے.(۴)
پھر مصیبت کے اوقات
کیلئے اسلام نے یہ ذکر سکھایا ہے کہ اناللہ وانا الیہ راجعون ہو جکی
- يونس غ :
Page 37
معنے یہ ہیں کہ ہم اسی کے ہیں اور بالآخر ہم نے بھی اسی کی طرف جانا ہے اگر کوئی عزیزہ مجھے مل گیا تھا تو یہ
خدا کی طرف سے ملاتھا اور اب جبکہ انہی واپس لے لیا ہے تو میرے لئے غم کی کونسی بات ہے پھر اگہ
کوئی گلاس ٹوٹ گیا تو کہدیا اپنا لِلهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون.یہ گلاس بھی آخر خدا تعالیٰ ہی نے دیا تھا
ہم نے بھی اسی کے پاس جانا ہے وہاں اور گلاس مل جائیں گے.غرض ہر نقصان کے وقت انا لِلهِ
و انا الیهِ رَاجِعُون کہنا انسانی فطرت کو زنگ سے صاف کر دیتا ہے.(D)
پھر اگر کوئی مکروہ بات یا مکروہ نظارہ پیش آجائے تو اس موقع کو اسلام نے ذکر کے بغیر نہیں چھوڑا
ملکہ ہدایت دی کہ جب کوئی مکروہ چیز دیکھو تو لا حول ولا قوة إلا بالله کہو یعنی ہر مصیبت
بچنے کی اور ہر بھلائی کو حاصل کرنے کی طاقت اللہ تعالیٰ کے سوا اور کہیں نہیں ملتی.(9)
پھر انسان کے اندر گناہ کی کوئی تحریک پیدا ہو تو ایسے موقعہ پر استغفر اللہ کا ذکر رکھ دیا
یعنی یک شیطانی حملوں سے اللہ تعالی کی پناہ مانگتا ہوں.(<)
پھر اعوذ باللہ کا ایک ذکر ہے جو ہر ایسے اہم کام کے شروع کرنے پر کیا جاتا ہے جس کے
راستے میں شیطانی روکوں کا امکان ہو مثلاً قرآن کریم پڑھنا ایک اہم کام ہے اور چونکہ شیطان اس میں
روکیں پیدا کرتا ہے اس لئے فرمایا فاذا قراتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ لِه
(^)
اس
کے علاوہ انسان سونے لگے تب بھی ذکر موجود ہے.چنانچہ ہدایت ہے کہ آیت الکرسی اور تینوں
قل پڑھو اور اپنے سینے پر پھونک لو.(۹)
آنکھ کھلے تب بھی ذکر موجود ہے.الحمد لله الذی احيانا بعدما اماتنا واليه النشور.(1.)
اسی طرح بیماری کے وقت بھی ذکر موجود ہے اور شفا ہو نے پر بھی ذکر الہی موجود ہے.پاخانہ جانا بظا ہر کتنا گند فعل ہے.مگر وہاں بھی مناسب حال ذکر موجود ہے.اللهم اني
: نحل غ :
:
Page 38
۳۲
اعوذ بك من الخُبث والخبائث.(۱۲)
پھر غسل کرنے لگو تب بھی ذکر موجود ہے.(۱۳)
میاں بیوی کے مخصوص تعلقات کو لو تو اس موقعہ پر بھی ہمارے کو ثر والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے
کہا ہے کہ جب تم آپس میں ملنے لگو تو خداتعالی کا پہلے ذکر کر یعنی اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا مِنَ الشَّيطن و
جنب الشيطن مَا رَزَقْتَنا پڑھ لیا کرو.غرض انسانی زندگی کا کوئی حصہ بھی ایسا نہیں خواہ وہ جذبات کے اظہار کا ہی ہو جہاں کوئی نہ
کوئی ذکر موجود نہ ہو.نماز اور زبانی ذکر ودھا کے علاوہ اسلام نے اصلاح نفس اور حصول معرفت کے بعض اور طریق بھی
بتائے ہیں جن کی مختصر تشریح درج ذیل ہے :-
- تفکر :- یہ خدا تعالیٰ کی ہستی تک پہنچنے میں مدد دیتا ہے اس کے معنے ہیں ذہنی اور فلسفیانہ
الجھنوں پر غور کرنا.تشکر :- خدا تعالیٰ فرماتا ہے ان شکرتم لازید نکمی جذبہ شکر تفکر کو مدد دیتا ہے
اور قرب الہی کی راہیں انسان پر کھلنے لگ جاتی ہیں.تذکر : تذکر اور تفکر میں فرق ہے.تفکر کسی ذہنی مسئلہ پیر غور کر نے کو کہتے ہیں اور تذکر کسی
پچھلے واقعہ کو یاد کر کے نتیجہ نکالنے کو کہتے ہیں جس کو عبرت بھی کہتے ہیں.یہ بھی دل کی صفائی کا ایک
بھاری ذریعہ ہے.۴ - شعور 1 - انسان کی فطرت میں جو جذبات ہیں اُن پر غور کر کے انہیں با ہر نکالنا شعور کہلاتا ہے فطرت
میں بہت سے احساسات اور جذبات پائے جاتے ہیں اگر ہم ان کو ابھاریں تو وہ بڑی ترقی کا مو
ہو سکتے ہیں.علم : یہ جگ بیتی کا نام ہے تذکرآپ بیتی کو کہتے ہیں ا فلم جگ بیتی کو کہانیوں میں بھی آتا ہے.آپ بیتی کہوں یا جگ بیتی اگر یہ علم ہو جائے کہ فلاں آدمی نے یہ یہ اعمال کئے تھے جن سے خرابیاں
پیدا ہوئیں تو بہت کچھ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے.ا
4 - فقہ : فقہ کا جذ بہ بھی انسان کو نیکی کی طرف لے جاتا ہے.قرآن کریم میںآتا ہے ولکن لا تفقهون
ابراہیم رکوع : : بنی اسرائیل : 1
Page 39
۳۳
فقہ ہر اس مسئلہ علمیہ کو کہتے ہیں جو ظاہر پر دلالت کرے اور اس کے ساتھ ہم اس کے باطنی
اثرات کو سوچیں.فکر مسئلہ فلسفہ کے لئے آتا ہے اور فقہ مسئلہ علمیہ کے لئے.- عقل :- اسی بھی اگر صحیح کام لیا جائے تو انسان کے اندر ایک ایسا جذبہ پیدا ہوتا ہے
ہو اُسے بُرے اور بھلے کی تمیز کروا دیتا ہے اور برائیوں سے روک دیتا ہے جیسے موٹر کی بریک
ہوتی ہے عقل بھی انسانی دماغ کی بریک ہے.- ابصار :- قرآن کریم میں آتا ہے.افلا تبصرون اس کے معنے ہیں روحانی آنکھ سے دیکھنا
اس سے بھی بڑی بڑی باتیں نکلتی ہیں جن سے انسان کی اصلاح ہوتی ہے.A
۱۰۰۹ - رویت و نظر -:- یہ دونوں قریب المعنے الفاظ ہیں لیکن ان میں فرق بھی ہے.جہانتک ظاہر
معنوں کا سوال ہے یہ آپس میں مشترک ہیں اور دیکھنے کے معنوں میں استعمال ہوتے ہیں.لیکن
ان میں فرق یہ ہے کہ رویت اس دیکھنے کو کہتے ہیں جن کے ساتھ شعور قلبی شامل ہو اور نظر
اُس دیکھنے کو کہتے ہیں جس کے ساتھ قوت فکر یہ شامل ہو.غرض تفکر تشکر تذکره شعور بعقل و دانش رویت اور نظریہ اس اسلامی عبادت کے حصے
ہیں جنہیں قرآن کریم نے الگ الگ موقعوں پر بیان کیا ہے دنیا کا اور کوئی مذہب نہیں جس میں
اس عبادت کا ایک حصہ بھی بیان ہوا ہو :
خلاص
یا در کو حقیقی نماز وہی ہے جس کی اثرات و برکات نماز پڑھنے والا خود مشاہدہ کر سے اور اپنی ذات میں
ایک پاک تبدیلی محسوس کر ہے.نمانہ بدیوں اور ناپسندیدہ باتوں سے روکتی ہے.یہ برائیوں سے بچنے کا قلعہ ہے خواہشات نفسانیہ کی
محافظ.دل کی غفلت اور شوخی نفس امارہ کا عمدہ اور کارگر علاج ہے.تزکیہ نفس اور اصلاح احوال کا موجب ہے.نماز وقت ضائع کرنیکی عادت سے بچاتی اور وقت کی قدرو قیمت کا شعور پیدا کرتی ہے.نماز سے باقاعدگی
اور متعدی
پیدا ہوتی ہے اور انسان کی عادات و خصائل اور اسکے دنیوی کام کاج میں ایک خاص قسیم
کا نظم اور اعتدال
پیدا ہوتا ہے.صبر و استقامت عزم و استقلال اور مصائب و مشکلات کے حل کی توفیق ملتی ہے.نماز سے انکساری و خاکساری - تواضع و بردباری بخشوع طبیعت خضوع جوارح اور حضو نفس
کی نعمت عطا ہوتی ہے.ل - قصص ع ، زخرف :
Page 40
۳۴
نماز سے باہمی تعاون اجتماعی اور قومی ضرورتوں کا احساس ترقی کرتا ہے اس
کے ذریعہ جماعتی
قوت و عظمت اور قومی شان و شوکت کی معنوی استعداد نشو و نما پاتی ہے.نماز سے مساوات
پیدا ہوتی اور باہمی ہمدردی کا جذبہ بڑھتا ہے.نماز میں تلاوت قرآن کریم کا موقعہ میسر آتا ہے جو حلاوت ایمانی کا باعث بنتا ہے.نماز
کے ذریعہ یاد الہی اور ذکر وفکر کی عادت پیدا ہوتی ہے.یہ حمد و ثنا تسبیح وتحمید اور اللہ تعالیٰ کی
گوناگوں نعمتوں پر اظہار
تشکر کا ذریعہ ہے.نماز میں دُعائے مستجار کے مواقع بکثرت میستر آتے ہیں خصوصا سجدہ قرب مقام اور دُعا کے
لئے موزوں تر حالت ہے.ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اقرب ما يكون العبد من ربه وهو
ساجد میں اسی طرف اشارہ ہے.نماز سے انسانی دل کو طراوت اور عقل کو جلا ملتی ہے.نور بصیرت بڑھتا ہے اور اطمینان قلب
نصیب ہوتا ہے.نماز سے حرارت ایمانی بڑھتی ہے اور محبت الہی جوش مارتی ہے.نما نه روحانیت کا سر
چشمہ ہدایت کا منبع معرفت الہیہ کا ذریعہ اور برکات سماویہ اور انوار
روحانیہ کا مہبط ہے.نماز کامیابی کی کلید تینگی اور آشفتہ حالی کا مداوا حزن و ملال کا تریاق اور یاس و حسرت
میں مسرت و شادمانی کا مژدہ جانفزا ہے مضطرب و مضطر محزون و مدیون مجبور و معذور اور
مظلوم و مہجور کے دل کو حقیقی راحت اور دردمندانہ اور متضرعا نہ دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ
ہے.غرض ایک مومن کے سبھی کام نماز اور دکھا سے ہی بنتے اور سنورتے ہیں.نمازہ انسان کو روحانیت کے علی معراج تک پہنچا دیتی ہے.حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم
الصلوة معراج المؤمن یہ اسی طرف اشارہ کرتی ہے.نمازہ سے انسان پر رویائے صالحہ.الہامات و مکاشفات اور مکالمات و مخاطبات الہیہ
کے دروازے کھلتے ہیں.اللہ تعالٰی سے تعلق بڑھتا ہے.یہاں تک کہ تبتل نام ہو کر انسان خدا
کا ہو جاتا ہے.اور خُدا میں جا ملتا ہے سیہ
نماز میں طریقت حصول حضور
سوال ہے : کبھی نماز میں لذت آتی ہے اور کبھی لذت جاتی رہتی ہے.اس کا کیا علاج ہے ؟
له يسلم كتاب الصلواۃ باب ما يقال في الركوع : : تفسیر کبیر رازی مت به جلد اول : سه : عفوظات ص۴۳۲ :
Page 41
قم
2"
جواب.ہمت نہیں ہارنی چاہیے بلکہ اس لذت کے کھوئے جانے کو محسوس کرنے اور پھر اس کو حاصل کرنے
کی سعی کرنی چاہیے جیسے چور مال اڈرا کر لے جاوے تو اس کا افسوس ہوتا ہے اور پھر انسان کوشش
کرتا ہے کہ آئندہ کو اس خطرہ سے محفوظ رہے اس لئے معمول سے زیادہ ہوشیاری اور مستعدی سے
کام لیتا ہے اسی طرح پر جو خبیث زمانہ کے ذوق اور انس کو لے گیا ہے تو اسے کس قدر
ہوشیار رہ سہنے کی ضرورت ہے اور کیوں نہ اس پر افسوس کیا جائے.انسان جب یہ
حالت دیکھے کہ اس کا انس و فوق جاتا رہا تو وہ بے فکر اور بے غم نہ ہو نماز میں ہے ذوقی
کا ہونا ایک سارق کی چوری اور روحانی بیماری ہے.جیسے ایک مریض کے منہ کا ذائقہ بدل
جاتا ہے تو وہ فی الفور علاج کی فکر کرتا ہے.اسی طرح پر جس کا روحانی مذاق بگڑ جاوے
اس کو بہت جلد اصلاح کی فکر کرنی لازم ہے یا اے
سوال :- ایک صاحب نے عرض کیا کہ نماز میں اگر مختلف خیالات پیدا ہوں تو کیا کیا جائے ؟
جواہے : " خیالات پیدا ہوں تو ان
کا مقابل کرد حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ تم
جب نماز کے لئے کھڑے ہو تو یہ سمجھو کہ تم اپنا فرض ادا کر رہے ہو اگر تمہیں خشوع و
خضوع نصیب ہو جائے تو یہ خدا تعالی کا ایک انعام ہوگا اور اگر خشوع وخضوع تنصیب
نہیں ہوتا اور تم بار بار کوشش کرتے ہو کہ تمہارے دل میں خیالات پیدا نہ ہوں تو پھر بھی
تم ثواب کے مستحق ہو.کیونکہ تمہاری شیطان سے لڑائی ہو رہی ہے اور جو شخص لڑائی کر رہا
مو وہ گنہگار نہیں ہوتا.جو شخص اپنے خیالات میں لذت محسوس کر ہے اور کہے کہ اگر خیالات پیدا ہوتے ہیں تو
بے شک پیدا ہوں وہ ضرور گنہگار ہے لیکن جو شخص ان خیالات کا مقابلہ کرتا ہے وہ
خدا کا سیاہی ہے اور ثواب کا مستحق ہے یہ
: فتادی مسیح موجود مل.: - الفضل و رجون ۱۹۳۳ سه ؟
Page 42
}
۳۶
جز دوم
نماز کی شرائط
جس طرح ایک اہم اور تعظیم الشان کام کو شروع کرنے سے پہلے مناسب تیاری کی ضرورت
ہوتی ہے اسی طرح نمازہ جیسی عظیم الشان عبادت
کو صحیح اور مکمل طور پر ادا کرنے کے لئے چند باتوں
کا پہلے کہ نا ضروری ہے جن کو شرائط نمازہ کہتے ہیں اور وہ پانچ ہیں :-
ا.وقت
- طہارت
۳.ستر عورتے یعنی پرده پوشی
قد
ه نيت
ہر ایک کی تفصیل درج ذیل ہے :-
Page 43
نماز کی پہلی شرط
وقت
پانچ اوقات میں نماز فرض ہے جن کی تفصیل یہ ہے :...-١ - فجر -: - رات جب ختم ہو جاتی ہے اور پو پھٹتی ہے تو مشرق میں سفیدی پھیلنے لگتی ہے.اس وقت کو فجر کہتے ہیں اور صبح صادق بھی.یہ وقت سورج نکلنے سے ذرا پہلے تک رہتا
ہے.معتدل علاقوں میں گھڑی کے لحاظ سے یہ ڈیڑھ گھنٹہ سے کچھ کم وقت بنتا ہے.اس
وقت میں دو رکعت نماز سنت اکیلے پڑھتے ہیں اور پھر دو رکعت نماز فرض با جماعت
ادا کرتے ہیں.افضل اور بہتر یہی ہے کہ کچھ منہ اندھیرے نماز شروع کی جائے، قرأت
لمبی ہو اور روشنی خوب پھیل جانے پر یہ ختم کی جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ نماز باجماعت
میں شامل ہو سکیں.ظہر کا وقت سورج ڈھلنے سے شروع ہوتا ہے اور اس وقت تک رہتا ہے جبکہ ہر چینہ کا
سایہ ایک مثل یعنی اس چیز کے برابر ہو جائے.اس وقت میں چار رکعت نماز سنت پھر چار
رکعت نماز فرض اس کے بعد دو رکعت نماز سنت ادا کی جاتی ہے.اگر کوئی چاہے تو
بعد ازاں دو رکعت نماز نفل پڑھ سکتا ہے اس سے زیادہ ثواب ملتا ہے نفل نماز کھڑے
ہو کر پڑھنے سے زیادہ تو اب ہوتا ہے.لیکن یہ نفل بیٹھ کر تھی پڑھ سکتے ہیں البتہ فرض اور
سنت نمازہ بلا عذر بیٹھ کر پڑھنا درست نہیں.اگر کسی مصروفیت یا مجبوری کی وجہ سے پہلی
مثل میں ظہر کی نماز نہ پڑھی جا سکے تو دوسری مثل یعنی ہر چیز کا سایہ دگنا ہونے تک یہ نمازہ
ہو سکتی ہے.گھڑی کے لحاظ سے ظہر کا سارا وقت معتدل علاقوں میں تین گھنٹے کے قریب بنتا ہے.ظہر کی نمازہ گرمیوں میں کچھ دیر ٹھہر کر اور سردیوں میں جلدی پڑھنا بہتر ہے جمعہ کی نماز کا بھی
وہی وقت ہے جو ہر کی نمازہ کا ہے گو یا جمعہ کی نماز در اصل ظہر کی نماز کے قائمقام ہے لیے
عصر دوسری مثل دیعنی ہر چیز کا سایہ دگنا ہونے) سے لے کر سورج ڈوبنے سے کچھ پہلے
تک کا وقت عصر کہلاتا ہے.گھڑی کے حساب سے معتدل علاقوں میں عصر کا وقت دو اڑھائی
ے.دیکھیں باب نماز
Page 44
PA
گھنٹے کے قریب بنتا ہے.اس وقت ہیں چار رکعت نمانہ فرض ہے اگر کوئی چاہیے تو فرضوں سے
پہلے چار رکعت سنتیں بھی پڑھ سکتا ہے.لیکن عصر کے فرض پڑھنے کے بعد کوئی سنت یا نفل
نمازہ جائز نہیں.اگر جلدی ہو اور کوئی ضروری کام در پیش ہو تو دوسری مثل کے شروع ہوتے
ہی عصر کی نماز پڑھی جاسکتی ہے لیکن افضل اور بہتر یہ ہے کہ دوسری مثل کے ختم ہونے اور
تیسری مشکل کے شروع ہونے پر عصر کی نماز پڑھی جائے.اسی طرح دھوپ کا رنگ پھیکا پڑنے سے
پہلے ہی نماز پڑھ لینی چاہئے کیونکہ بل کسی مجبوری کے زیادہ دیر کرنا اور ایسے وقت میں نماز
پڑھنا کہ دھوپ کا زنگ زرد پڑ جائے اور سورج غروب ہونے کے قریب ہو جائے نا پسندید اور کروں گا.جیسا کہ بیان ہو چکا ہے کہ کسی مصروفیت کی وجہ سے اگر دیر ہوجائے تو ظہر کی نماز دوسری
ہیں پڑھ سکتے ہیں اور اگر جلدی ہو تو عصر کی نماز بھی اس مثل میں ہو سکتی ہے اس لحاظ
سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ دوسری مثل کا وقت در اصل ظہر کی نمازہ کا بھی ہے اور عصر کی نماز کا بھی مینی
یہ وقت دونوں میں مشترک ہے.یہی وجہ ہے کہ سفر بیماری یاکسی اجتماعی دینی کام میں عد وفقیت
کی وجہ سے ظہر اور عصر کی نمازیں جمع بھی ہو سکتی ہیں.کیونکہ ان دونوں نمازوں
کا وقت کچھ تھوڑے
سے
سے فرق کے ساتھا اپنے اندر تسلسل رکھتا ہے.لے
م.مغر ہے.سورج ڈوبنے سے لے کر مغربی افق میں نظر آنیوالی شفق یعنی شرفی کے غائب ہونے تک
کا وقت مغرب
کہلاتا ہے.گھڑی کے حساب سے معتدل علاقوں میں یہ وقت ڈیڑھ گھنٹہ سے کچھ کم نبتا
ہے.اس وقت میں تین رکعت فرض نمانہ پڑھی جاتی ہے اس کے بعد دو رکعت نماز سنت اور
پھر حسب موقع و مرضی دو رکعت نماز نفل بھی پڑھ سکتے ہیں.شرفی کے بعد مغربی افق پر جو سفیدی نمودار ہوتی ہے اُسے بھی شفق کہتے ہیں اس سفیدی کے
غائب ہونے کا جو وقت ہے وہ مغرب اور عشاء کے درمیان مشترک ہے یعنی اگر کسی مجبوری کی وجہ سے
دیر ہو گئی ہو تو اس وقت میں مغرب کی نمازہ بھی ہو سکتی ہے اور اگر ضروری کام کی وجہ سے جلدی
ہو تو اسی وقت میں عشاء کی نما نہ بھی پڑھ سکتے ہیں ایسے ہی جائز مجبوری کے پیش نظر مغرب
اور عشاء کی نما نہ میں جمع بھی ہو سکتی ہیں..ه - عشاء.عشاء کا وقت شفق یعنی سفیدی غائب ہونے کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور فجر
کے طلوع سے کچھ پہلے تک رہتا ہے لیکن بہتر اور افضل وقت نصف شب تک ہے.عشاء کے وقت میں چار رکعت نماز فرض اور پھر دو رکعت سنت ہے.دو رکعت نفل نمانہ کا
اه :- دیکھیں باب جمع نماز کتاب ہذا :
Page 45
۳۹
گھنٹے
ذکرہ بھی بعض روایات میں آتا ہے.وتر نماز کی تین رکعتیں ہوتی ہیں.اس نماز کا وقت عشاء کی فرض نماز پڑھنے کے بعد سے
شروع ہوتا ہے اور طلوع فجر تک رہتا ہے جس شخص کو رات کے پچھلے حصہ میں اُٹھ گنے کا اطمینان
نہ ہو اس کے لئے بہتر یہی ہے کہ وہ عشاء کی نماز کے ساتھ ہی وتر پڑھ لے تاہم عشاء کی نماز کے
بعد سو جانا اور پھر رات کے پچھلے حصہ میں اُٹھ کر تہجد کی آٹھ رکعت نماز پڑھنا بہت سی برکات
کا موجب ہے اس نماز کو تہجد کی نمازہ کہتے ہیں.تہجد کے بعد اور فجر کے طلوع ہونے سے پہلے
و تریر هنا عشاء کی نماز کے ساتھ وتر پڑھنے سے زیادہ افضل ہے اس
کی زیادہ ثواب ملتا ہے.تبھول جانے یا سوئے رہنے کی وجہ سے اگر وقت پر نماز نہ پڑھی جاسکے تو جس وقت انسان کو
یاد آئے یادہ بیدار ہو اسی وقت تیاری کر کے وہ نماز پڑھ لے کیونکہ اس کی اس فوت شدہ نماز کے
لئے اللہ تعالٰی کے ہاں یہی وقت مقدر تھا.غیر معمولی علاقے جہاں دن رات چوبیس گھنٹے سے زیادہ کے ہیں یا دن رات اگرچہ چو ملیں گے
کے ہیں لیکن ان میں باہمی فرق اتنا زیادہ ہے کہ شر آن وسنت کی رو سے نمازوں کے پانچ
معروف اوقات کی تفریق بہت مشکل ہے مثلاً قطب شمالی کے ایسے علاقے جہاں شفیق تاہم اور
شفق صبح کے درمیان امتیانہ نہیں ہوسکتا یعنی درمیان میں فسق حائل نہیں ہوتا وہاں نمازوں کے
اوقات گھڑی کے حساب سے اندازہ سے مقرر کئے جائیں گے اور اوقات کے تعین کے لئے
سورج کے طلوع و غروب کے اعتبار سے معروف علامات کی پابندی ضروری نہ ہوگی.نیز ایسے
علاقوں میں نمازوں کے اوقات چوبیس گھنٹوں کے اندر اس طرح پھیلا کہ مقرر کئے جائیں گے کہ
ان کا درمیانی وقفہ معتدل علاقوں کے اوقات نماز کے درمیانی وقفہ سے حتی الوسع ملتا جلتا
ہو.مجموعی آبادی کی معاشرتی عادت کے لحاظ سے ان علاقوں میں کام کاج کا وقت خواہ
سورج موجود نہ ہو دن اور آرام اور سونے کا وقت خواہ سورج آسمان پر چمک رہا ہورات
شمار ہوگا.ے: دیکھئے فوت شدہ نمائندوں کی قضاء کتاب ہذا :
ہے شفق سے مراد وہ شرفی اور سفیدی ہے جو سورج غروب اور طلوع ہونے کے وقت افق پر نمودار ہوتی ہے.حق سے مراد وہ اندھیرا ہے جو سورج غروب ہو جانے اور شرفی اور سفیدی غائب ہو جانے کے بعد نضا پر چھا جاتا ہے :
Page 46
نماند او کی وقت میں پڑھنا افضل ہے تاہم امام الزمان اور خلیفہ وقت کی مصروفیت کے
پیش نظر یا لوگوں کی سہولت کی غرض سے سویر سے یا دیر سے نماز پڑھنے کا جو وقت مقرر کیا
جائے وہ افضل ترین ہے کیونکہ اہم جماعتی ذمہ داریوں کے لحاظ سے خلیفہ وقت بہتر جانتا
ہے کہ کس کام کو مقدم اور کسی کو ڈخر رکھنا موجب خیر و برکت ہے.اسی طرح نماز یا جماعت
کے لئے وقت مقرر کرنے میں اس بات کو مد نظر رکھنا بھی منشاء شریعیت کے عین مطابق
ہے کہ لوگ نماز کے لئے بسہولت اور زیادہ تعداد میں کس وقت جمع ہو سکتے ہیں تا کہ زیادہ
سے زیادہ لوگ جماعت میں شامل ہو کر زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کریں.اوقات نماز کی حکمت : - نماز کی اصل غرض یہ ہے کہ تھوڑے تھوڑے وقفہ کے بعد
خدائے حتی وقیوم کا نام لیا جائے کیونکہ جس طرح گرمی کے موسم میں تھوڑے تھوڑے سے وقفہ کے بعد انسان
ایک ایک دو دو گھونٹ پانی پیتا رہتا ہے نا کر گلا تر ہے اور اس کے جسم کو طارت پہنچتی ہے اس طرح کفراور بے ایمانی کی
گرم بازاری میں اسانی رح کو دو اور تازگی پہنچانے کیلے الہ تعالی نے تھوڑے تھوڑے وقفہ کے بعد نماز مقرر کی
ہے تا کہ گناہ کی گرمی اس کی روح کو جھلس نہ دے اور مسموم ماحول اس کی روحانی طاقتوں کو
مضمحل نہ کرد سے خوشی ہو یا غمی ہر حالت میں انسان کو نماز کے ذریعہ خدا تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے
کا موقع ملتا ہے جب دنیا کا نظر فریب حسن اسے اپنی طرف کھینچتا ہے تو نماز کی مدد سے
وہ خُدا کی طرف جھکتا ہے.نماز کے لئے وقت مقررہ کرنے سے اجتماعیت کی روح کو زندہ
رکھنے کا موقع ملتا ہے اس طرح لوگ بآسانی جمع ہو سکتے ہیں.نیز وقت کی تعیین کو خود انسان
کی اپنی مرضی پر نہ چھوڑنے میں یہ حکمت ہے کہ تا انسان کو پر وقت نماز ادا کرنے کی فکر رہے
اور اس کا ذمہ داری کا احساس بیدار رہے اگر وقت کی تعیین خود انسان پر چھوڑ دی جاتی
تو وقت کی پابندی کی اہمیت جاتی رہتی اور اس میں سستی ظاہر ہونے لگتی.چونکہ قلبی کیفیات بدلتی رہتی ہیں اس لئے ایک ہی وقت میں دیر تک عبادت میں
مشغول رکھنے کی بجائے مختلف اوقات میں عبادت کا حکم دیا گیا ہے کیونکہ لمبے وقت میں دیر
تک توجہ قائم رکھنا مشکل ہو جاتا ہے اس سے طبیعت اکتا جاتی ہے لیکن اس کے برعکس
اگر وقت مختصر ہو اور وقفہ وقفہ کے بعد کئی بار عبادت بجالانے کا موقع ملے تو بشاشت
قائم رہتی ہے عبادت سہل ہو جاتی ہے اور عبودیت کے اظہار کا بھی بار بار موقع ملتا
ہے اس کی یاد دل میں تازہ رہتی ہے اس کا سارا وقت عبادت الہی میں ہی طرف ہوتا
Page 47
ہے اور اس طرح سے انسان دنیا کے کاموں میں مصروف رہنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ
سے غافل نہیں ہوتا اور دنیا میں رہ کر بھی وہ اسے علیحدہ رہتا ہے اور " دست در کار دل
با یارہ کی مثل اس پر صادق آنے لگتی ہے.۳ - سچی محبت ہمیشہ اپنے ساتھ بعض ظاہری علامات بھی رکھتی ہے اور محبت کی ایک بڑی
علامت یہ ہے کہ انسان اٹھتے بیٹھتے اپنے محبوب
کا ذکر کرتا ہے اور اس کی یاد اپنے دل میں
تازہ رکھتا ہے جب کوئی شخص اپنے کسی عزیز کو یاد کر لیتا ہے تو اس کی محبت دل میں تازہ
ہو جاتی ہے اور اس کی صورت آنکھوں کے سامنے آجاتی ہے.نماز بھی اللہ تعالیٰ کی یاد اور
اس کی ملاقات کا ایک ذریعہ ہے اس لئے اسلام نے یہ ضروری قرار دیا ہے کہ انسان
تھوڑے تھوڑے وقفہ کے بعد خدا تعالیٰ کا نام لے اور نماز کے لئے کھڑا ہو جائے..نماز کے لئے متعدد اوقات مقرر کرنے میں ایک حکمت یہ ہے کہ انسان
پر جتنی بڑی ذمہ داری
ہوتی ہے.اتنی ہی شدت سے اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی اُسے بار بار مشق کرائی جاتی ہے
تاکہ یہ اطمینان رہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے اس کا حکم ماننے کے لئے پوری طرح سے مستعد
اور تیار ہیں.بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اس زمانہ میں مشاغل اس قدر بڑھ گئے
ہیں کہ اتنا وقت نمازوں کے لئے نکالنا مشکل ہے.اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ اگر
نماز کی غرض محبت الہی کی آگ بھڑکا کر اللہ تعالیٰ کی صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لئے
سہولت بہم پہنچانا اور اس کے لئے مشق کرتا ہے تو جس زمانہ میں مشاغل بڑھ جائیں اس
زمانہ میں نمازہ بار بار پڑھنے کی اہمیت بڑھ جانی چاہیے کیونکہ ظاہر ہے کہ جس وقت مقصد کو
بھلا دینے کے سامان زیادہ ہوں گے اس وقت مقصد کی طرف بار بار توجہ دلانے کی
بھی زیادہ ضرورت ہوتی ہے.پس اس زمانہ میں اگر دنیوی مشاغل بڑھ گئے ہیں تو نمسانہ
کی ضرورت بھی بڑھ گئی ہے پھر اگر نماز صرف اظہار عقیدہ کا ایک ذریعہ ہوتی تب تو یہ
اعتراض کچھ وزن بھی رکھتا مگر جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ نمازہ کی غرض صرف اقرار عبودیت
نہیں بلکہ اس کی غرض انسانی نفس میں وہ استعداد پیدا کرتا ہے جس کی مدد سے وہ مادی دنیا
سے اڑ کر روحانی عالم میں پہنچ سکے اور اس کا دباغ جسمانی خواہشات میں ہی الجھ کر نہ
رہ جائے بلکہ اعلیٰ اخلاق کو حاصل کرے کیونکہ قرآن کریم کی تصریح کے مطابق نمازہ کی مدد سے
انسان بدیوں اور بدکرداریوں سے بچتا اور اعلیٰ اخلاق حاصل کرتا ہے اور اس طرح اس کا وجود
Page 48
۴۲
بنی نوع انسان کے لئے زیادہ سے زیادہ مفید بن جاتا ہے اور ملک و ملت کا وہ ایک زیادہ فائدہ
بخش جزو بن جاتا ہے اور جو عمل اپنے اندر یہ خوبیاں رکھتا ہو مادی اشتغال کی کثرت کے زمانہ میں
اس کی ضرورت کم نہیں ہوتی بلکہ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے.- نماز کے پانچ اوقات مقرر کرنے میں یہ حکمت بھی ہے کہ :.ز أنا سورج نکلنے کے بعد انسان دنیا کے کاروبار میں مصروف ہو جاتا ہے اور دوپہر کے
وقت وہ کچھ ستانے اور کھانے پینے کی ضرورت محسوس کرتا ہے اس وقفہ میں یاد الہی کیلئے
بھی تھوڑا سا دقت رکھ دیا تا کہ انسان کا روبار کی توفیق پر اپنے خدا کا شکر بجالائے اور آئندہ
کے لئے مزید برکات حاصل
کرنے کی دعا کر سکے.یہ زوال کا وقت انسان کو اس طرف بھی
توجہ دلاتا ہے کہ جس طرح سورج کی چمک میں فرق آنے لگا ہے اسی طرح انسان کی جوانی بھی
زوال کی زد میں ہے اور اس کا قلب بھی غفلت کے نزنگ سے اپنی آب کھو سکتا ہے.اس لئے انسان کو اس تغیر سے سبق سیکھنا چاہیئے اور روشنی اور خوشحالی کے اس منبع کی طرف
اسے توجہ کرنی چاہیئے جس پر کبھی زوال نہیں آتا تا کہ اس کی روح زوال کے اثرات سے محفوظ
رہے اور اس کی جسمانی صحت بھی قائم رہے.حدیث شریف میں آتا ہے کہ ظہر کے وقت رحمانی
آسمان کے درواز سے کھولے جاتے ہیں اور صبح سے دوپہر تک کے اعمال اور پر کو اٹھائے جاتے
ہیں.ایسے وقت میں نما نہ روحانی صعود کا موجب ہے اور اپنے لئے ایک اچھی شہادت مہیا کرتا ہے.(ii) عصر کے وقت کا دوبارہ سمیٹنے کی فکر ہوتی..اس لئے مصروفیت اپنی انتہا
ہوتی ہے.مختلف امور انسانی توجہ کو اپنی طرف کھینچتے ہیں.اس وقت میں نماز مقریہ
کرنے سے یہ ثابت کرنا ہے کہ جو خدا کا ہے وہ ایسی حالت میں بھی اپنے رب کو نہیں
بھونتا اور سب باتوں سے اپنی توجہ ہٹا کر اُسی کی طرف اپنی توجہ پھیر لیتا ہے.در مختلف
روگوں کے باوجود اپنے خُدا کے حضور جا حاضر ہوتا ہے.پھر یہ وقت تفریح اور کھیل کود
کا ہے.اس وقت میں نماز کا حکم : سے گراد پر متوجہ کیا کہ انسان کو بے اعتدالی اور ہے
راہروی سے ہر حال میں بچنا چاہیئے اور کھیل میں اپنے اصل فرائض سے غافل نہیں ہو جانا
چاہیے ، نیز اس طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے کہ آسمانی سورج کی طرح انسانی زندگی کا آفتاب
بھی رفتہ رفتہ ڈھل رہا ہے اور غروب کے قریب پہنچنے والا ہے اس لئے اس فرصت کو
غنیمت سمجھنا چا ہیئے اور اسے ضائع نہیں ہونے دینا چاہیئے.
Page 49
۴۳
(iii) مغر کے وقت سورج ڈوب چکا ہوتا ہے تاریکی کے سائے بڑھنے لگتے ہیں خطرے کا وقت آپہنچتا
ہے ظلمت کے بندے بدی کی تیاریوں میں لگ جاتے ہیں ایسے وقت میں عبادت رکھ کر اس طرف توجہ دلائی
کر ان حالات میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی پناہ گاہ نہیں اور تاریخی کی ظلمتوں سے نجات پانے کے لیے دہی ایک
آفتاب عالمتاب ہے جس کی روشنی دائمی ہے.(۷) عشاء کی نماز کے ذریعہ سونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے اس کے فضلوں کا شکر بجا لانے
مصیبتوں سے نجات پانے کے لیے دعا کرنے کا موقع بہم پہنچایا گیا ہے نیز یہ وقت فراغت کا ہے اس
وقت طبیعت عیش و آرام اور کھیل تماشہ کی طرف راغب ہوتی ہے اگر عبادت کا رجحان نہ ہو تو ان
فضولیات اور بڑے مشاغل میں وقت صرف ہوگا اور ان میں انہماک کی وجہ سے وہ دیر سے سوئے گا اس
طرح صبح دیر سے بیدار ہو گا.صبح کی نماز بھی وقت پر نہ پڑھ سکے گا اور دوسرے اہم کام بھی وقت پر شروع
نہ کر سکے گا علاوہ ازیں اس وقت میں نمانہ مقرہ کر کے اس طرف بھی توجہ دلائی ہے کہ انسان سونے سے پہلے
اپنا معاملہ نہات کرلے تا اگر سوئے ہوئے موت آجائے تو وہ محاسبہ اور حسرت کی آگ سے بچ جائے
م انسان جن خیالات میں سوئے گا وہی رات بھر اس کے دماغ میں چکر لگاتے رہیں گے اس نماز اور ذکر الہی کے
معاً بعد وہ سوئے گا تو پاکیزہ خیالات اس کے دماغ میں سما جائینگے اس طرح اس کی نیند بھی عبادت کا
حصہ بن جائے گی.(۷) فجر کی نماز کے لیے اٹھنا باعث برکت ہے کیونکہ یہ بر کانت الہیٰ کے نزول کا وقت ہے ان
برکات سے حصہ لینے کی تمنا سچے ایمان کا عین اقتضاء ہے جس طرح سورج کی آمد آمار تاریک ماحول کو
روشن کر دیتی ہے اسی طرح صلوۃ اور دعا کی روشنی سے مایوسی کی تاریکیاں ہوا ہو جاتی ہیں مسرتوں کی
عطر بیز ننک چاروں طرف پھیل جاتی ہے.نماز کے یہ پانچ اوقات مقرر کرنے میں ایک اور حکمت یہ ہے کہ یہ نمازیں ہمارے پانچ مختلف
باطنی تغیرات کا فوٹو اور فطرت انسانی کا مقتضی ہیں کیونکہ ہماری زندگی کے لازم حال پانچے اندرونی
تغیر ہیں.سب سے پہلے جب انسان کو اطلاع ملتی ہے کہ اس پر ایک مصیبت آنے والی ہے مثلاً جیسے
اُس کے نام عدالت کی طرف سے وارنٹ گرفتاری آئے تو اس سے اس کے اطمینان میں خلل واقع ہوگا
اور اس
کی خوشحالی متاثر ہوگی.انسان کی یہ حالت زوال کے وقت کے مشابہ ہے کیونکہ اس حالت سے اس
کے اطمینان اور اس کی خوشحالی میں زوال آنا شروع ہوا اس اس پریشان کن صورت حال کے یہ نتائج سے بچنے
Page 50
کے لیے نماز ظہر مقرر کی گئی جس کا وقت زوال آفتاب سے شروع ہوتا ہے گویا مصیبت کی اطلاع
کے ساتھ ہی اس سے چھٹکارا پانے کی جدوجہد کا اُس نے آغاز کر دیا.دوسرا تغیر اس وقت انسان پر آتا ہے جبکہ مصیبت سریہ آکھڑی ہوتی ہے جیسے مثلاً بذریعہ
وارنٹ گرفتار ہو کر انسان حاکم کے سامنے پیش ہو یہ وہ وقت ہے جبکہ خوف سے انسان کا خون خشک.اور ستی کا نور اس سے رخصت ہونے کو ہوتا ہے اور امید و بیم ، ڈر اور خوف
کی عجیب کیفیت
انسان
دو چار ہوتا ہے سو یہ حالت اس وقت سے مشابہ ہے جبکہ آفتاب کا نور کم ہوجاتا ہے اور صریح نظر
آتا ہے کہ اب غروب نزدیک ہے اس صورت حال کے مقابل اندرونی بے اطمینانی کو دور کرنے کے لیے
عصر کی نماز مقرر ہوئی اور نجات کے لیے جد وجہد میں تیزی آگئی.تیرا تغیر انسان پر اس وقت آتا ہے جبکہ اس مصیبت سے نجات پانے کی امید منقطع ہو جاتی
ہے اور مایوسی اسے آگھیرتی ہے مثلاً جیسے فرد جرم لگ جاتی ہے اور مخالفانہ گواہ اس کی ہلاکت کیلئے گذر
جاتے ہیں یہ وہ وقت ہے جبکہ انسان کے حواس جواب دینے لگتے ہیں اور وہ اپنے تئیں ایک قیدی
سمجھنے لگتا ہے سو یہ حالت اس وقت سے مشابہ ہے جبکہ آفتاب غروب ہو جاتا ہے اور روشنی کی کوئی
کردن باقی نہیں رہتی اس حالت کے مقابل روحانی مایوسی کی ہلاکت سے بچنے کے لیے نماز مغرب مقرر
ہوئی گویا نجات کے لیے جدو جہد اور تیز ہوگئی.چوتھا تغیر انسان پر اس وقت آتا ہے جبکہ مصیبت میں انسان بالکل پھنس جاتا ہے
تاریخی انسان کا احاطہ کر لیتی ہے مثلاً جب کہ شہادتوں کے بعد منزا کا حکم سنایا جاتا ہے اور پولیس مجرم
کو جیل کی طرف لے جانے لگتی ہے.سو یہ حالت اس وقت سے مشابہ ہے جبکہ رات آ جاتی ہے اور ہر
طرف اندھیرا چھا جاتا ہے اضطراب کی اس ناقابل برداشت حالت کے مقابل روحانی سکون
کو باقی رکھنے
کے لیے گویا بطور آخری چارہ کار نماز عشاء مقرر ہوئی جس میں گویا یہ سنتی ہے کہ خدا ہی کی ذات ہے
جسے سب طاقتیں ہیں اُس کے در کے سوا انسان کدھر جائے اور اپنی فریاد کیسے سنائے پس وہ اسی
کے دروازے پر گرتا ہے اور اس کے حضور اپنی فریاد کو انتہا تک پہنچا دیتا ہے.پانچواں تغیر انسان پر اس وقت آتا ہے جبکہ اس کی جدو جہد اور آہ و زاری آخر سنگ لوتی
ہے.خدا کا رحم جوش مارتا ہے.مصائب کے بادل چھٹ جاتے ہیں اور تاریکی کے بعد آخر کار صبح امید
نمودار ہوتی ہے اور پھر دن کی روشنی پہلی کی سی چمک دمک کے ساتھ ظاہر ہو جاتی ہے.مواس
حالت امید و مسرت کے مشابہ روحانی خوشی کا سجدہ شکر نماز فجر کی صورت میں متعین ہوا.
Page 51
۴۵
غرض نمازوں کے اوقات انسان کے روحانی تغیرات کا خلق اور نماز میں آنے والی مصیبتوں کا علاج ہیں
انسان نہیں جانتا کو چڑھنے والا نیا ن کی قضاء و قدر کولائے گا.پس قبل اس کے جو دن چڑھے انسان
اپنے مولائے حقیقی کی جناب میں تضرع کرے تا وہ اس کے لیے خیر و برکت کا دن پڑھائے.اوقات مکروبه
مندرجه ذیل وقتوں میں نماز پڑھنا مکر وہ اور نا پسندیدہ ہے.جب سورج طلوع ہو رہا ہو اس وقت سے لے کر نیزہ بھر سورج بلند ہونے تک کوئی نماز نہیں
پڑھنی چاہیئے نہ فرض اور نہ نفل.البتہ اگر دیر سے جاگ آئی یا کوئی اور حقیقی روک پیدا ہوگئی اور تیاری وغیرہ
کر کے تجر کی فرض نماز شروع کی، ابھی ایک رکعت پڑھی تھی کہ سورج نکلنے لگا تو ایسی صورت میں دوسری رکعت
سورج نکلنے کے دوران میں بھی انسان پڑھ سکتا ہے.مین دوپہر کے وقت جب سورج بالکل سر میر ہو اس وقت میں فرضوں یا نفلوں میں سے کوئی نماز نہیں
-
پڑھنی چاہیئے.تاہم جمعہ کے دن اس وقت میں مسجد میں دو رکعت نفل پڑھنے کی اجازت ہے.جب سورج غروب ہو رہا ہو تو اس وقت میں بھی کوئی فرض یا نفل نماز جائز نہیں البتہ اگر کسی معقول منذر
کی وجہ سے عصر کی نماز وقت پر نہ پڑھی جاسکی ہو اور ابھی ایک رکعت پڑھی تھی کہ سورج ڈوبنے لگا ایسی صورت
میں بقیہ تین رکعتیں سورج ڈوبنے کے دوران بلکہ اس کے بعد بھی پڑھی جاسکتی ہیں.یہ تو وہ اوقات تھے جن میں بلا عذر کوئی نماز بھی جائز نہیں نہ فرض نہ نقل، لیکن مندرجہ ذیل اوقات
میں صرف نفل نماز مکروہ ہے.فجر کے طلوع ہونے کے بعد سورج نکلنے تک دو رکعت سنت کے علاوہ کوئی
اور نقل نماز جائز نہیں.عصر کی نماز پڑھنے کے بعد نفل نماز جائز نہیں.عید کے دن سورج نکلنے کے بعد
عید گاہ میں نقل جائز نہیں نہ عید کی نماز سے پہلے اور نہ عید کی نماز کے بعد.نماز با جماعت ہو رہی ہو تو اس
وقت مسجد میں اپنے طور پر سنت یا نفل نماز جائز نہیں.تاہم خانہ کعبہ یعنی مسجد الحرام میں کسی وقت بھی سنت
یا نفل نماز پڑھ سکتے ہیں کیونکہ وہاں ہر وقت طواف کعبہ کر سکتے ہیں اور ہر طواف کے بعد دو رکعت نماز پڑھنا
ضروری ہے جسے طواف کی نماز کہتے ہیں.سورج گر مین کی صورت میں نماز کسوف کسی وقت بھی پڑھی جاسکتی ہے
سورج نکل رہا ہو یا ڈوب رہا ہو مین دوپہر ہو یا عصر کی نماز کے بعد ہوتیں وقت بھی گرمین لگے نماز شروع
کر دینی چاہیے کیونکہ اس نمازہ کا سبب سورج گرہن ہے وہ نہیں وقت لگے اسی وقت نماز پڑھنا مسنون
Page 52
ہو گا.دن کے کچھ حصوں میں نماز پڑھنے سے منع کرتے ہیں یہ حکمت ہے کہ تا اس طرف توجہ ہو کہ اصل مقصد
اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری ہے خدا جب کسے نماز پڑھو نماز پڑھیں گے اور جب کسے نماز نہ پڑھو تو
با وجود عمده حالات میتر آنے کے نماز پڑھنا کوئی نیکی نہ ہوگی کیو نکنیکی اور عیادت وہی ہے جسے اللہ تعالی پسند
کرے.ان اوقات میں ممانعت نماز کی ایک اور حکمت یہ ہے کہ ان میں سے بعض اوقات میں خصوصاً طلوع و
غروب آفتاب کے وقت مشرک اور بت پرست اپنے معبودان باطلہ کی پرستش کرتے ہیں گویا یہ اوقات فروغ
شرک و کفر کا نشان بن گئے تھے اس لیے توحید کے پرستاروں کو کفر و شرک کے اس شعار سے دور رہنے کی
ہدایت کی گئی اور اسلام کی مخصوص عبادت کے صحیح صحیح اوقات جو اپنے اندر روحانی فوائد رکھتے تھے
مقرر کئے گئے اس ممانعت سے اس حکمت کی طرف بھی توجہ دلائی کہ کوئی وقت ایسا بھی ہونا چاہیے جس میں انسان
کا دماغ فارغ ہو ورنہ مسلسل مصروفیت سے وہ بے کار ہو جائے گا.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار
فرمایا جب انسان نماز پڑھتے پڑھتے تھک جائے تو اسے چاہیئے کہ آرام کرے گویا اس مقصد کے پیش نظر بطور
علامت یہ اوقات جبری فراغت کے رکھے گئے تاکہ کوئی وہمی جو میں گھنٹے ہی نماز پڑھنے میں نہ گار ہے اور
اس کے لیے کچھ وقت ایسے بھی آجائیں مین میں وہ فارغ ہونے اور نماز چھوڑنے پر مجبور ہو.
Page 53
نمازیں پانچ فرض ہیں
سوال: - اہلِ قرآن - قرآن میں تین نمازیں ثابت کرتے ہیں نیز یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ نماز جو موجودہ مسلمان ادا
کرتے ہیں اس میں غیر قرآنی الفاظ ہیں.قرآن میں ایک سجدہ ہے مگر نماز میں دو ادا کرتے ہیں
جو قرآن کے احکام کے خلاف ہے ؟
جواب :.اہل قرآن کا یہ خیال غلط ہے کہ قرآن مجید سے صرف تین نمازیں ثابت ہوتی ہیں قرآن مجید میں
جس طرح ان تین نمازوں کا ذکر ہے جو اہل قرآن مانتے ہیں اسی طرح باقی دو نمازوں کا بھی ذکر ہے اور
ان سب کا طریہ بیان ایک ساہی ہے.پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے ہی امت مسلمہ پورے تسلسل
کے ساتھ روزانہ پانچ بار
نماز پڑھتی چلی آئی ہے قرآن کریم میں بالا جمال پانچ فرض نمازوں کا ذکر ہے اور حدیث میں ان کی تفصیل موجود
ہے.غرض ایک لیے عرصہ کا تاریخی تسلسل اور امت مسلمہ کا تواتر عملی پانچ نمازوں کو قطعی طور پر ثابت کرتا
ہے.تاریخ میں کہیں ایک واقعہ بھی نہیں تاکہ امت کی اکثریت نے کبھی تین نمازیں پڑھی تھیں اور پھر غلط طور
پور پانچ نمازیں ہوگئیں.غرض یہ ایک انتہائی مضحکہ خیز خیال ہے کہ اتنے تو اتر اور نسل سے ہونے والی عبادات
کے متعلق یہ شبہ پیدا کیا جائے کیونکہ یہ تو تاریخ کا ایک عملی واقعہ ہے کوئی نظریاتی مسئلہ نہیں کہ عقلی تخیل کی بناء
پر اس میں کسی قسم کے اختلاف کی گنجائش نکالی جاسکے.قرآن کریم میں آتا ہے کہ تم نماز میں دعائیں کرو اب دعا تو انسان اسی چیز کی کرتا ہے میں کی اسے ضرورت
ہو اور یہ ضروری نہیں کہ اسکی ہر ضرورت قرآنی الفاظ سے ہی ظاہر ہو اسی طرح قرآن کریم نے کہا ہے کہ اپنے رب
کی تیج کرد اب لازماً جو اس حکم کی تعمیل کریگا وہ بصورت تکلم اسے بیان کریگا.غرض یہ سوال بھی محض ایک
عقلی ڈھکوسلے پر مبنی ہے کہ نماز کے سارے الفاظ قرآنی ہوں غیر قرآنی کوئی لفظ نہ ہو آخر یہ قرآن کریم کی کیس
آیت میں لکھا ہے کہ شروع سے لیکر آخر تک نماز میں صرف قرآن کریم کی آیات ہی پڑھتے پہلے جاؤ.قرآن کریم میں تو
صرف استفدر ہے کہ نماز میں قرآن بھی پڑھو.سو ہر مسلمان اس حکم کو مانتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے اور قرآن کریم
کے کسی حصہ کا نماز میں پڑھنا فرض جانتا ہے.قرآن کریم میں کہیں نہیں کھا ہے کہ نماز میں صرف ایک سجدہ کیا جائے بلکہ حکم یہ ہے کہ ناز میں سجدہ کرد
Page 54
۴۸
کتنے سجدے کر د یہ نہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل اور قول سے بتایا در اصل جیسا کہ شروع میں بیان
کیا گیا ہے نماز ایک ایسی عبادت ہے جسے مسلمان دن میں پانچ بار بجالاتے ہیں اور آغاز اسلام سے اتک اس
عبادت کوغیر منقطع تو اتر حاصل رہا ہے حضور اکرم صلی اللہ علہ وسلم کو صحابہ کرام نے دکھا.صحابہ کو نا امین نے دیکھا
اسی طرح پر نسل چلتا چلا آیا پیس کس طرح ممکن ہے کہ مسلمانوں نے نماز کے اہم ترین حصوں کو ترک کر دیا ہواور
یہ تبدیلی چپ چاپ ہوگئی ہو.نہ تاریخوں میں اس
کا ذکر ہو اورنہ ہی مسلمانوں کا چودہ سوسالہ عمل ہی اُسے ظاہر
کرتا ہو.غرض اس زمانے کے ان نئے شارمین کو دو راستوں میں سے ایک راستہ لازماً اختیار کرنا پڑیگا.یا تو وہ اس بات سے انکار کریں کہ رسول للہ صل اللہ علیہ ہم کام ان کے لیے حجت ہے اور قرآن نے آپ کی یہ جو
شان بیان کی ہے کہ لتبين للناس مانزل اليهم اسے وہ نہیں مانتے یا پھر یہ مائیں کہ اصل نماز
تو وہی ہے جو آنحضرت نے پڑھی ہے لیکن یہ لوگ اپنی نئی نماز ایجاد کرینگے.سوال:.کیا عین دوپہر کے وقت نماز پڑھ سکتے ہیں.اگر یہ نہیں ہو سکتا تو جمعہ کے دن تعطیہ سے پہلے لوگ کثرت
سنتیں پڑھتے ہیں اس کے متعلق کیا فیصلہ ہے ؟
ستجواب : عین دوپہر کے وقت نماز پڑھنا درست نہیں.باقی خطبہ سے پہلے سنتیں پڑھنا جائز ہے کیونکہ فروری
نہیں کر خطبہ میں دوپہر کے وقت شروع ہو بلکہ بہتر یہ ہے کہ سورج ڈھلنے پر مناسب وقفہ کے بعد خطبہ شروع کیا
جائے تاکہ دوست سنتیں وقت پر پڑھ سکیں.سوال:- اگر اشراق کی نماز پڑھتے ہوئے زوال کا وقت آجائے تو کیا نماز فاسد ہو جائے گی ؟
جواب : اگر نفل نماز پڑھتے ہوئے زوال کا وقت ہو جائے تو نماز فاسد نہ ہوگی بلکہ اس کی تکمیل کرنی
چاہیئے.علاوہ ازیں زوال کے وقت نماز پڑھنے کی ممانعت میں وہ شدت نہیں جو غروب آفتاب با طلوع
کے وقت میں ہے کیونکہ جمعہ کے دن نیز مسجد الحرام میں اس وقت میں نقل نماز پڑھنے کی اجازت ہے اور
یہ احادیث سے ثابت ہے.زوال سے مراد وہ وقت ہے جب سورج عین سمت الراس میں ہو اور زوال کے قریب ہو.در اصل زوال کے لفظ کا استعمال قریبی حالت کے اعتبار سے ہے ورنہ جب دلوک شروع ہو جاتا ہے تو نماز کا
وقت صحیح شروع ہو جاتا ہے اور مکروہ وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے.
Page 55
۴۹
نماز کی دوسری شرط
طهارت
نماز کیا ہے ؟ اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہونا - قرب الہی حاصل کرنے کی کو نہ
کوشش کرتا ہیں
اس کے لیے جہاں دل کا خلوص اور باطن کی پاکیزگی ضروری ہے وہاں جسم کی صفائی اور کپڑوں کی پاکیزگی
بھی ایک لازمی شرط ہے.کیونکہ اگر ہم گندے اور نا پاک نیم میلے کچیلے اور خراب کپڑوں کے ساتھ ایک
معزز شخص کے پاس جانا نہیں چاہتے اور نہ ایسے ناصاف شخص سے خود عنا پسند کرتے ہیں تو پھر ایسی
خراب حالت میں اللہ تعالیٰ کے حضور ہی جانا کیونکر پسندیدہ قرار دے سکتے ہیں.اسی فطرتی تقاضا کے ماتحت اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمائی ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے پاک جسم اور
پاک کپڑے ہونے چاہئیں نیز جس جگہ نماز پڑھی جائے اس کا پاک وصاف ہونا بھی ضروری ہے.طہارت کے ایک منے یہ ہیں کہ جسم کے کسی حصہ پر کوئی گند لگا ہوانہ ہو مثلاً انسان کا بول و براز ،
مادہ منویہ کسی جانور کا گو بر ، پیشاب، مرغی کی بیٹ.زخم کی پیپ جسم سے بہ نکلنے والا خون حرام جانور
یا مردار کا گوشت اور خون - کتے اور دوسرے حرام جانوروں کی رال اور اُن کا جوٹھا ، گلی کوچوں کا ناپاک
کیچڑ.یہ سب حقیقی نجاستیں ہیں.ان میں سے کوئی نجاست اگر کسی وجہ سے جسم کے کسی حصہ کو لگ جائے تو
پانی سے دھو کر جسم کو پاک وصاف
کر لینا چاہیے.اچھی طرح ایک بار دھونا کافی ہے، لیکن اگر تین بار دھویا
جائے تو زیادہ بہتر ہوگا.اس ظاہری صفائی کے علاوہ نماز پڑھنے کے لیے غسل اور وضو بھی ضروری ہے غسل اور وضو کو طاقت
حکمی کہتے ہیں اور حسین حالت کی وجہ سے یہ طہارت ضروری ہوتی ہے اس حالت کا نام نجاست حکمی یا
حدث ہے.موجبات غسل
مین باتوں کی وجہ سے نہانا ضروری ہو جاتا ہے انہیں موجبات غسل کہتے ہیں اور وہ یہ ہیں.
Page 56
مباشرت یعنی زن وشو ہر کا مخصوص جنسی تعلق قائم کرنا.احتلام یاکسی اور وجہ سے شہوانی ہیجان کے
ساتھ مادہ منویہ کا نکلنا.عورت کے ایام ماہواری یعنی نخون حیض کا ختم ہونا حیض سے مراد ایام ماہواری ہیں.یعنی بالغہ عورت کی وہ طبعی حالت جس کی وجہ سے کم و بیش ہر ماہ تین سے لے کر دس دن تک خون آتا ہے
یہ خون ختم ہونے پر بنانا ضروری ہوتا ہے جن دنوں میں یہ خون نہیں آتا وہ طہر کے دن کہلاتے ہیں.ولادت کے بعد خون نفاس کا ختم ہونا نفاس سے مراد وہ خون ہے جو بچہ کی پیدائش کے بعد جاری ہوتا ہے
اور زیادہ سے زیادہ چائنیں دن تک رہتا ہے کم سے کم کے لیے کوئی اندازہ نہیں بعض اوقات دومین دن
میں ہی ختم ہو جاتا ہے اس خون کے ختم ہونے کے بعد بھی تھا نا ضروری ہوتا ہے.ان صورتوں میں نہائے
بغیر نماز پڑھنا جائز نہ ہوگا اور اگر سخت سردی یا بیماری وغیرہ کی وجہ سے نہانے سے صحت کو نقصان
پہنچنے یا زیادہ بیمارہ ہو جانے کا ڈر ہو تو تھانے کی بجائے تمیم کی بھی اجازت ہے.نماز کی حالت باطنی پاکیزگی - روحانی نشاط - ظاہری طہارت اور جسمانی مستعدی
کی مقننی ہے لیکن نا پاکی
کی حالتیں جسم میں گرانی ، نقاہت، کمزوری اور روحانی کسلمندی کا موجب بنتی ہیں اور بہانے سے یہ کیفیت
دور ہو جائے گی جسم میں تازگی دسبک ساری آجائے گی اور پوری بشاشت کے ساتھ انسان نماز کے لیے
کھڑا ہوگا.اور اس طرح جذبات لطیفہ ، ارواح طیبہ اور واردات روحانیہ کا وہ مور دین سکے گا جو نمانہ
کا مقصد اصلی ہے.غیرمسلم قبول اسلام کے بعد جب نماز پڑھنے لگے تو پہلے نہائے وضو کرے اور پھر اس کے بعد نماز
شروع کرے تاکہ قبول اسلام کے بعد جب پہلی بار وہ خدا کے حضور جائے تو باطنی طہارت کے ساتھ ظاہری
طور پر بھی پاک وصاف ہو.اس کے علاوہ حیض و نفاس کے دنوں میں نماز پڑھنا.قرآن کریم کی تلاوت کرنا اور
روزہ رکھنا جائز نہیں.نماز معاف ہے اس وجہ سے رمضان کے جو روز سے رہ گئے ہوں بعد میں ان کی قضاء
ضروری ہے.پیدا ہونے والے بچہ کو بھی نہلا نا ضروری ہے.تجہیز و تکفین سے پہلے میت کو غسل دینا بھی ضروری
ہے تاکہ پاک وصاف حالت میں اس
کی نمازہ جنازہ پڑھی جاسکے اور پھر اس
کی تدفین عمل میں لائی جاسکے.علاوہ ازیں جمعہ اور عید کے دن، حج کا احرام باندھنے اور میدانِ عرفات میں وقوت کے وقت
نہانا مسنون ہے اس طرح بیماری سے شفایاب ہونے کے بعد غسل صحت بھی باعث برکت ہے.جو شخص
میت کو نہلائے اُسے بعد میں خود بھی نہا لینا چاہیے.موسم کو مد نظر رکھتے ہوئے روزانہ یاکبھی کبھار نہاتے
رہنا صحت وصفائی کے اعتبار سے بہت مفید رہتا ہے..
Page 57
۵۱
نہانے کے فرائض و آداب
نہانے کے تین فرض ہیں.(۱) کلی کرنا (۲) پانی سے ناک صاف کرنا (۳) اس کے بعد سارے
بدن پر پانی ڈالنا یا تک کہ جسم کا کوئی حصہ خشک نہ رہے.عورت کے سر کے بال اگر گھنے اور گند ہے
ہوئے ہوں تو ان کا کھونا اور سارے بالوں کو تر کرنا ضروری نہیں بلکہ سر پر تین بار پانی ڈال کر مسح کے
رنگ میں سر پر ہا تھ پھیر لینا کافی ہے.نہانے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ نہانے والا موسم کے مطابق گرم یا سرد صاف ستھرا پانی
استعمال کرے.پہلے استنجاء کرے پھر وضو کرے یعنی بسم اللہ پڑھکر ہاتھ دھوئے اس کے بعد کتی
کرے اور ناک میں پانی ڈالے منہ اور کہنیوں تک ہاتھ دھوئے سر کا مسح کرے.پھر بدن پر تین بار
پانی ڈالے.پہلے دائیں طرف اور پھر بائیں طرف.نہاتے وقت جسم کو اچھی طرح مکنا بھی چاہیے.اس
طرح کوئی اچھا سا صابن یا میل دور کرنے والی کوئی مفید چیز استعمال کرنا بھی آداب غسل میں شامل
ہے.جس حالت میں نہانا ضروری ہے اس حالت میں نہائے بغیر نہ انسان نماز پڑھ سکتا ہے نہ قرآن کریم
کی باقاعدہ تلاوت کر سکتا ہے اور نہ ہی مسجد میں جا سکتا ہے.بیت الخلاء اور استنجاء
قضائے حاجت کے لیے بیٹھنے یا اُٹھنے کے وقت پردہ کا لحاظ رکھنا ضروری ہے یا تو بنے
ہوئے صاف ستھرے بیت الخلاء میں جائے یا پھر دور جنگل میں کسی اوٹ والی جگہ میں جانا چاہیئے
آبادی کے پاس جہاں لوگوں کی آمد ورفت عام ہو چلتے راستہ پر سایہ دار جگہ یا درخت کے نیچے جہاں
کام کاج یا آرام کے لیے لوگوں کے آ بیٹھنے کا احتمال ہو قضاء حاجت نہ کرے اس طرح بیت الخلاء
میں نگے پاؤں نہ جائے بلکہ جوتی یا چپل پہن کر جائے.استنجاء اور صفائی کے لیے پانی کا انتظام ہونا
چاہیے اور اگر پانی نہ مل سکے تو پھر مٹی کے ڈھیلے یا اس قسم کی صفائی کے لیے بنا ہوا کا نفذ ساتھ لے
جائے اور کم از کم تین بار استعمال کرے.استنجاء یعنی صفائی بائیں ہاتھ سے کرے دایاں ہاتھ
استعمال نہ کرے.بیت الخلاء میں قدم رکھنے سے پہلے اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخَبثِ وَالْخَبَائِثِ
یعنی اسے میرے خدا بڑے اثرات اور خبیث قسم کی بیماریوں سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں کے
Page 58
۵۲
الفاظ میں دعا کرے.پہلے بایاں پاؤں اندر رکھے حتی الوسع قبلہ کی طرف منہ یا پیٹھ کرکے نہ بیٹھے قضائے
حاجت کے وقت باتیں نہ کرے فارغ ہونے کے بعد نکلتے وقت پہلے دایاں قدم باہرکھے اور ساتھ
غفرانك الحمد لله الذي اذهب عنى الاذی کے یعنی میرے خدا تیری مغفرت چاہتا ہوں
تیری حمد اور تعریف کرتا ہوں کہ تو نے مجھے تکلیف دہ گند سے نجات دی اور مانیت بخشی.فارغ ہونے
کے بعد صابن یا مٹی سے مل کر پانی سے ہاتھ دھونے چاہئیں.موجبات وضو
جن وجوہات سے وضو کرنا ضروری ہو جاتا ہے انہیں موجبات وضو یا اسباب وضو کہتے ہیں.اور وہ یہ ہیں :
قضائے حاجت یعنی پیشاب، پاخانہ کرنے یا پیشاب کے راستہ کسی اور رطوبت کے نکلنے.ہوا
خارج ہونے ، ٹیک لگا کر یا لیٹ کر سونے اور بے ہوش ہو جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے.ایسی
صورت حال پیش آنے کے بعد جب نماز پڑھنی ہو تو پہلے وضو کیا جائے اور پھر نماز پڑھی جائے.کیونکہ وضو کے بغیر نماز صحیح نہیں ہوتی اگر کسی کو ریح خارج ہوتے رہنے پیشاب قطرہ قطرہ گرتے رہنے یا
استحاضہ یعنی حیض و نفاس کے مقررہ دنوں کے علاوہ بھی نخون جاری رہنے کی بیماری ہو اور اس وجہ سے
اس کا وضو نہ ٹھہرتا ہو تو وہ معذور ہے اس کے لیے ہر نماز کے وقت ایک بار وضو کر لینا کافی ہے اس
وقت میں اس وضو سے جو نماز چاہیے وہ پڑھ سکتا ہے کیونکہ اس بیماری سے اُس کا وضو نہیں ٹوٹے گا.وضو کرنے کا طریق
جب کوئی شخص وضو کرنے لگے تو بسم اللہ پڑھے، پاک صاف پانی لے کر ٹہنیوں تک ہاتھ
دھوئے پھر تین بار کلی کرے منہ کو اچھی طرح صاف کرنے کے لیے مسواک یا برش استعمال کرنا
چاہیے اور اگر یہ میسر نہ ہو تو انگلی سے دانت صاف کرے ، پانی چلو میں لے کر ناک میں ڈالے اور
اسے اچھی طرح صاف کرے.پھر تین بار سارا چہرہ دھوئے، داڑھی گھنی ہو تو ہاتھ کی انگلیوں سے
بالوں میں تعلال کرنا اچھا ہے اس کے بعد کہنیوں سمیت تین بار ہا تھ دھوئے.پھر
پورے سر کا اور
کانوں کا مسح کرے یعنی پانی سے ہاتھ تر کر کے سارے سر پر پھیرے پھر انگشت شہادت کانوں کے
اندیہ کی طرف اور انگوٹھے کانوں کے باہر کی طرف پھیرے.پھر تین بار ٹخنوں سمیت پاؤں دھوئے
Page 59
۵۳
پہلے دائیں عضو کو دھوئے اور پھر بایاں.اس کے علاوہ ترتیب کو مد نظر رکھنا اور اعضاء کو لگاتا ہے
و ھونا بھی ضروری ہے.یہ نہ ہو کہ منہ دھو لیا اور پھر اسکی خشک ہو جانے پر ہاتھ دھونئے.ایک
وضو سے انسان کئی نمازیں پڑھ سکتا ہے کیونکہ جب تک وضو توڑنے والی کوئی بات ظاہر نہ ہو و صو قائم رہتا ہے.فرائض وضو
وضو کے چار فرض ہیں :-
(1) پورا منہ دھوتا (۲) کہنیوں سمیت ہاتھ دھونا (۳) سرکا مسح کرنا یہ نوں سمیت پیٹوں
دھونا ہے اگر ان میں سے کوئی فرض رہ جائے تو وضو نہیں ہوگا
سنن وضو
وضو شروع کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا پھر پہنچوں تک ہاتھ دھونا کلی کرنا.اس کے لیے مہاک
استعمال کرنا.تاک صاف کرنا.ہر عضو کو تین بار دھونا.سارے سر کا ایک بار مسیح کرنا اس کے ساتھ
کانوں اور گردن کا مسح کرنا.گھنی داڑھی کی صورت میں خلال
کرنا.قرآن کریم میں مذکور ترتیب
کا لحاظ رکھنا.یکے بعد دیگرے ہر عضو کو دھونا.پہلے دائیں عضو کو اور پھر بائیں کو.پانی کا
استعمال مناسب مقدار میں کرنا.اس میں افراط و تفریط سے بچنا.یہ سب باتیں آنحضرت صلی اللہ علیہ ولم
کی سنت اور آپ کے ارشادات کے عین مطابق اور آداب وضو میں شامل ہیں.وضو کی حکمت
موجبات وضو سے کسلمندی اور غفلت سی پیدا ہوجاتی ہے جو وضو سے دور ہو جاتی ہے اور
جسم میں تازگی اور مستعدی آجاتی ہے عبادت الہی کے لیے توجہ اور یکسوئی حاصل ہوتی ہے اس
ظاہری پاکیزگی سے باطنی طہارت کی طرف توجہ پھرتی ہے گویا ایک طرح سے تصویری زبان میں انسان یہ
دعا کرتا ہے کہ جس طرح یہ ظاہری پانی ان اعضاء کی میل کچیل کو دور کر رہا ہے اسی طرح توبہ کا پانی
اس باطنی میل کو دور کر دے جو ان اعضاء کی غلط کرداری کی وجہ سے چڑھ گئی ہے.نیز وضو کی صورت میں جسم کے سات حصوں کو دھونا ان حصوں سے صادر ہونے والے
Page 60
۵۴
گناہوں سے تائب ہونے کی طرف اشارہ کا رنگ رکھتا ہے.زبان - آنکھ کان.دماغ.ہاتھ.پاڈی
اور شرمگاہ.یہ سات اعضاء خدا کی نافرمانی یا فرمانبرداری کا موجب بنتے ہیں تمثیلی زبان میں ان
ظاہری اعضاء کو دھو کر باطنی طور پر طاہر ہونے کی تمنا کا اظہار پایا جاتا ہے.اعصابی امراض کے ماہرین کے تجربہ سے ثابت ہے کہ ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کو ٹھنڈا
کرنے سے جذبات اور خیالات کی رو کو بدلا جا سکتا ہے پھر دھو کے ذریعہ پراگندہ خیالات کی رو کو
روک
کر انسانی ذہن کو ذکر الٹی کی طرف پھیرا جاتا ہے اس سے اعتدلال حاصل ہوتا ہے.علاوہ ازیں
وضو میں جن اعضاء کو دھویا جاتا ہے بالعموم وہی کھلے رہتے ہیں گرد و غبار اُن پر پڑتا رہتا ہے اس
لیے اُن کو دھونے سے ایک تو یہ صاف ہو جاتے ہیں دوسرے ان کا دھونا آسان بھی ہے کیونکہ کپڑے
وغیرہ اتارنے کی ضرورت نہیں پڑتی.اخراج ریح سے وضو ٹوٹنے میں ایک خاص حکمت یہ بھی ہے
کہ تا مسجد کا تقدس قائم رہے.مجالس اور اجتماعات کی فضاء جو پہلے ہی اثر دھام کے تنفس کی
وجہ سے ایک حد تک خراب ہو جاتی ہے بلا روک ٹوک اخراج ریخ سے مزید مکدر نہ ہونے پائے
جرابوں پر مسح کرنا
اگر وضو کر کے جرا میں پہنی گئی ہوں تو اس کے بعد وضو کرتے وقت جرا میں انا نا اور پاؤں
دھونا ضروری نہیں بلکہ بصورت اقامت ایک دن رات اور بصورت سفر تین دن رات ان پر منح
ہو سکتا ہے.یہ مدت جرابیں پہننے کے وقت سے نہیں بلکہ وضو ٹوٹنے کے وقت سے شروع
ہوگی.جب تک جبرا میں استعمال کے قابل ہوں اُن پر مسح کیا جا سکتا ہے.پس اگر جراب تھوڑی
بہت پھٹی ہوئی ہو مثلاً شگاف میں سے کچھ ایڑی نظر آتی ہو.اندازاً تین انگل کے برا برتشنگان
ہو لیکن استعمال کے قابل ہو تو بھی کوئی حرج نہیں ایسی جرابوں پر مسح جائز ہے.مسیح کا مسنون طریق یہ ہے کہ ہم نقطہ کو پانی میں تر کر کے ان کی انگلیاں پشت یا یعنی
جرابوں کے اوپر پھیری جائیں یا اُن پر گیلے ہاتھ رکھ دیئے جائیں.چمڑے کے موزے یا بند بوٹ پر
بھی مسح جائز ہے انہیں بین کر نماز پڑھی جا سکتی ہے اگر ایک جراب اتر جائے تو پھر دوسری جراب
بھی اتار کر اور دونوں پاؤں کو دھو کر دوبارہ حرا نہیں پہنی چاہئیں یہ جائز نہیں کہ ایک پاؤں کو
دھو لیا جائے اور دوسرے پاؤں جس میں جواب پہنی ہوئی ہے اُس پر مسح کیا جائے اگر وضو
ہو لیکن مسح کی مدت ختم ہوگئی ہو تو جرا ہیں اتار کر صرف پاؤں دھو لینا کافی ہے سارا وضو کرنا
Page 61
۵۵
ضروری نہیں.اگر کوئی عضو زخمی ہو اور اُسے دھونا نقصان دہ ہو خواہ اس پر پٹی بندھی ہوئی ہو یا گھنا
ہو وضو کرتے وقت اس عضو کو دھونے کی بجائے اُس پر مسیح کر لینا کافی ہے.مسیح کی اجازت میں رعایت اور سہولت کے پہلو کو مد نظر رکھا گیا ہے تا کہ انسان بار بار بالوں
کو اتارنے اور سینے کے تردد سے بچ جائے جرج اور تکلیف میں نہ پڑے.تیم اور اس کے مسائل
:
اگر پانی کا استعمال مشکل ہو مثلا انسان بیمایہ ہو یا پاتی ملمانہ ہو یا پانی نجس ہو تو نماز
پڑھنے کے لیے نہانے یا وضو کرنے کی بجائے انسان تمیم کرنے یعنی صاف و باک مٹی یا کسی غبار
والی چیز اور اگر ایسی کوئی چیز نہ ملے تو ویسے ہی کسی ٹھوس چیز پر صحت نماز کی نیت سے بسم اللہ
پڑھکر دونوں ہا تھ مارے اور ان کو پہلے منہ پر پھیرے اور پھر دونوں ہاتھوں پر عام حالات
میں پہنچوں تک مسیح کافی ہے لیکن اگر با میں کھلی ہوں کوٹ یا موٹر وغیرہ نہ پہنا ہوا ہو کھلی آستینیں
ہوں تو پھر کہنیوں تک مسح کرنا چاہئیے.اگر ہاتھوں
پر زیادہ مٹی لگ گئی ہو تو مسح کرنے سے
پہلے انہیں جھاڑ لینا جائز ہے.غسل واجب کے لیے بھی اُسی طرح تم کیا جاتا ہے جس طرح وضو کے لیے کیا جاتا ہے اس
تمیم کے بعد انسان پاک ہو جاتا ہے اور جو نماز چاہے پڑھ سکتا ہے گھر میں بھی اور مسجد میں جاکر
بھی اس کے لیے کوئی روک نہیں جب تک پانی نہ ملے یا انسان اس کے استعمال پر قادر نہ ہو
تیم سے نماز پڑھی جاسکتی ہے.اسی طرح ایک نیم سے کئی نمازیں پڑھنا بھی جائز ہے جن باتوں سے
وضو ٹوٹ جاتا ہے اُن سے تیمیہ بھی ٹوٹ جاتا ہے اس کے علاوہ پانی مل جانے یا تندرستی کے
یا
بعد پانی کے استعمال پر قادر ہو جانے سے بھی تیم بانی نہیں رہتا اور وضو کرنا ضروری ہو جاتا ہے.تیم سے اگر چہ ظاہری صفائی کی غرض پوری نہیں ہوتی لیکن خیالات کو مجتمع کرنے، توجہ
کو ایک طرف لگانے اور ایک.اہم اور با برکت کام کرنے کے لیے مستعدی پیدا کرنے کا مقصد
اس سے حاصل ہو جاتا ہے اس کے علاوہ تصویری زبان میں منکسرانہ دعا کا رنگ بھی اس میں پایا
جاتا ہے گویا تمیم کرنے والا کہتا ہے اسے ہمارے خدا تیرے پانی کے بغیر ہم خاک آلود ہونے
جاتے ہیں تیری یہ نعمت ہمیں نہ ملی تو ہمارے جسم گردو غبار سے کٹ جائیں گے.اس لیے تو جلد
پانی عطا فرما.
Page 62
ង់។
پانی اور اس کے مسائل
طہارت حاصل کرنے کا اصل ذریعہ پانی ہے پاک وصاف پانی استعمال کرنا چاہئیے.بارش
چشمے.کوئیں.تالاب - دریا اور سمندر کا پانی پاک ہے دوسری چیزیں اس سے دھوئی اور پاک کی
جاسکتی ہیں صحت کے اعتبار سے جو پانی مضر ہو شلاً اس میں پتے گل سڑ جائیں یا کیڑے وغیرہ پڑ
جائیں تو اسے صاف
کر لینا چاہیئے.پانی یہ رہا ہو یا کافی پھیلاؤ میں کھڑا ہو تو معمولی نجاست پڑنے
سے وہ ناپاک نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ نجاست کی وجہ سے اس کا رنگ یا گو یا مزہ بدل جائے اس صورت
میں وہ نا قابل استعمال ہو جائے گا.اگر پانی تھوڑا یعنی تین چار مشک سے کم ہو اور اس میں کوئی نہیں
چیز پڑ جائے تو وہ ناپاک ہو جائے گا.خواہ اس گند کی وجہ سے اس کا رنگ، بو یا مزہ نہ بدلا ہو اس
سے نہ وضو جائز ہوگا اور نہ نہانا بلکہ اس کی بجائے تمیم کرنا چاہیئے اس طرح اس پانی سے کپڑے
دھونا اور برتن صاف کرنا بھی جائز نہیں.جو پانی وضو یا نہانے کے لیے استعمال ہوا ہو با وجود ضرورت
اور دوسرا پانی نہ مل سکنے کے اس استعمال شدہ پانی سے دوبارہ وضو کرنا یا نہانا درست نہیں میٹی
کے ملنے سے پانی جو گلا ہو جاتا ہے اس کی پاگیز گئی میں کوئی فرق نہیں آتا کیونکہ مٹی پاک ہے اس
جوگی
**
لیے وہ پانی بھی پاک ہے اور اس سے وضو وغیرہ جائز ہے.ا
پانی سے دھونے اور نجاست دور ہو جانے سے کپڑا پاک ہو جاتا ہے لیکن اگر نجاست نظر
نہ آتی ہو یا اس کا نشان دور نہ ہو سکتا ہو تو پھر کپڑے کو تین بار ضرور دھونا چاہیئے ہر بار دھونے
کے بعد اُسے نچوڑا جائے اس طرح سے وہ پاک ہو جائے گا.چھوٹا دودھ پیتا بچہ اگر کپڑے
پر پیشاب کر دے تو صحت نماز کے لیے ان کو مل کر دھونا ضروری نہیں صرف پانی چھڑک دینا کافی
ہوگا.پٹرول وغیرہ کے ذریعہ ڈرائی کلین سے بھی کپڑا پاک ہو جاتا ہے لو ہے یا کسی دوسری دھات سے
بنی ہوئی چیز مثلاً چھری وغیرہ کو اگر گند لک جائے تو مٹی پر اچھی طرح رگڑنے یا آگ میں رکھنے سے وہ
پاک ہو جائیگی.اس طرح ہوتی پر گند لگ جائے تو زمین پر رگڑنے اور چلنے پھرنے سے وہ پاک ہو جائگی کاسکو
سین کر نماز پڑھی جاسکتی ہے تاہم صفائی کے پیش نظرمسجد میں جوتی پہن کرنہیں جانا چاہیئے.گند پڑنے سے اگر زمین
نجی ہوگئی ہو تو دھوپ سے سوکھ جائے اورگند کا اتر زال ہو جانے سے وہ پاک ہو جائیگی اسے پانی سے دھونے کی ضرورت
نہیں.سور اور کتے کے سواباقی ہر جانور کا چپڑا دھوپ میں سکھانے یا رنگنے سے پاک ہو جاتا ہے اسکی جوتی
وغیرہ بنائی جا سکتی ہے اس طرح اُسے مصلے کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں.
Page 63
۵۷
وضو سے ازالہ گناہ
طهارت
برکات وضو
یہ جو لکھا ہے کہ وضو کرنے سے گناہ دور ہو جاتے ہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ خدا تعالیٰ
کے چھوٹے چھوٹے حکم بھی ضائع نہیں جاتے اور ان کے بجالانے سے بھی گناہ دور ہوجاتے
د نور القرآن جلد ۲ ص۳۵.ہیں.مسواک
(فتاوی مسیح موعود من )
حضرت صاحب مسواک کو بہت پسند فرماتے ہیں اور علاوہ مسواک کے اور مختلف
چیزوں سے دن میں کئی دفعہ دانتوں کو صاف کرتے.اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی میں سنفت
تھی نہیں سب کو چاہیے کہ اس طرف بھی توجہ رکھا کریں.(بعد ۲۸ فروری شاه )
(فتاوی مسیح موعود هنا )
پگڑی پر مسح
حضرت مسیح موعود نے فرمایا.گڑی پر مسیح میں اختلاف ہے، میری سمجھ میں جائز ہے.(219.0
الحکم ۱۲۴ نومبر 11
(فتاوی مسیح موعود قت)
Page 64
۵۸
جرابوں پر مسح کرنا
جرابوں پر مسح کرنا جائز ہے.حکمت مسح کے لحاظ سے بھی اور صراحت حدیث کے لحاظ سے بھی اس
کا جواز موجود ہے.حکمت تو یہ ہے کہ پاؤں میں جو موزے یا جرابیں پہنی ہوئی ہیں انہیں بار بار اتارنا نہ
پڑے.حرج سے بچانا مقاصد شریعت کا بنیادی اصول ہے.نیز حدیث میں آتا ہے :-
عن مغيرة بن شعبة قال توضا النبي صلى الله عليه وسلم ومسيح
على الجوربين والنعلين
(ترمذی جلد امث باب مسح على الجوربين )
یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور جرابوں اور تعلین پر سے فرمایا.سوال: - شیعہ قرآنی آیت سے استدلال کرتے ہوئے پیروں پر مسح کرتے ہیں کیا یہ جائز ہے ؟
جواب : - آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا عمل کسی آیت کے معنی کو معین کر دیتا ہے ہیں
جب حدیثوں اور تاریخ کی کتابوں میں تواتر کے ساتھ مذکور ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ
صحابه وضوء میں پاؤں دھویا کرتے تھے اور مسیح صرف اسی صورت میں کرتے جبکہ موزے یا جرابیں پہنی
ہوئی ہوتی تھیں تو پاؤں پر صرف مسح کرنے کا حکم قرآن سے کس طرح ثابت ہوا.آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کا ایک کام اللہ تعالیٰ کے کلام کے معنی بتانا بھی تھا اور آپ نے وارجلكم الی الکعبین
کے جو معنے قولاً وعملاً بتائے وہ وہی تھے کہ پاؤں کو ٹخنوں تک دھویا جائے.نیز اگر پاؤں پر
مسح کرنا ہی مقصد تھا تو پھر الی الکعبین کہنے کی کیا ضرورت تھی اس طرح تو یہ ایک بے معنی
کلام بن جاتا ہے.باقی عربی کے اسلوب کے لحاظ سے پاؤں دھونے کے معنے لینے میں کوئی غلطی
نہیں.ماہرین علوم کا ایک مانا ہوا قاعدہ ہے کہ بعض اوقات قریب ہونے کی وجہ سے پہلے کا اعراب
دوسرے پر آجاتا ہے اس کو اصطلاح میں جو جوار کہتے ہیں علاوہ ازیں اس کی دوسری قرأت ارحکم
یعنی نصب کے ساتھ بھی ہے اور یہ قرأت متواتر ہے جس سے واضح ہے کہ اس کا تعلق اغسلوا سے
ہے نہ کہ امسحوا سے ہر حال وضوء ایک سنت متواتر ہے.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے
جب سے یہ آیت نازل ہوئی اس پر مسلمان عمل کرتے پہلے آئے ہیں.روزانہ اس کام کو کئی بار کیا
جاتا ہے ایسے متواتر عمل کے بارہ میں یہ سمجھنا کہ مسلمانوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں
تھا کہ وہ پاؤں دھوتے ہیں یا مسح کرتے ہیں بالکل خلاف واقع بات ہے اور یہ ثابت کرنا کہ
Page 65
۵۹
صحابہ کی اکثریت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں پاؤں پر مسح کرتی تھی اس کا بار ثبوت شیعہ
حضرات پر ہے.سوال : جب ہوا خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو ڈکار لینے سے کیوں نہیں ٹوٹتا جبکہ دونوں
ہوائیں انتڑیوں سے خارج ہوتی ہیں اور بدبودار ہوتی ہیں.جواب : - نص شریعت اصل بنیاد ہے چونکہ نص میں صرت ریح“ کے خارج ہونے کو وضو توڑنے کا
موجب قرار دیا گیا ہے اس لیے اس حد پر رکنے کا حکم ہے.آگے اس پر قیاس کرنے کی اجازت نہیں
کیو نکہ عبادات یعنی احکام تعبدی میں قیاس
کو بطور ماخذ شریعت تسلیم نہیں کیا گیا.پیشاب پاخانہ کی راہ سے جو چیز بھی نکلے یا اندر جائے اس سے وضو ٹوٹ جائے گا.یہ
امر نواقض وضو میں شامل ہے، لیکن منہ کی یہ صورت حال نہیں ، منہ سے کوئی چیز نکلے یامنہ
کے ذریعہ
اندر جائے جیسے سانس لینا تھوکنا، کھانا کھانا، پانی پینا اس سے وضو نہیں ٹوٹتا.پس اسی طرح
ڈکا ر سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا.باقی یہ اپنی جگہ الگ حکم ہے کہ کھانا کھانے پانی پینے سانس لینے
تھوکنے، بلغم پھینکنے، چھینک مارنے یاڈ کا رینے کے آداب اور اُن کے متعلق اسلامی ہدایات
کھلے
کیا ہیں اور محبیس کے حقوق ان پر کس حد تک اثر انداز ہوتے ہیں..ڈکارمنہ کے راستے اُس ہوا کے خارج کرنے کا نام ہے جو کھانے وغیرہ کے ساتھ دوسری
نالیوں کے راستے اندر چلی جاتی ہے اور بالعموم معدہ کے اوپر کے کم متقی حصوں میں جمع ہوتی ہے
لیکن ریح مخزن نجاسات یعنی انترلوں اور معدہ کے نچلے حصہ سے نکلتی ہے اور اس کا مخرج
یعنی نکلنے کا راستہ بھی متعفن اور نجس ہوتا ہے اس لیے ڈکار کی نسبت یہ زیادہ مردہ کیفیت
ہے اور اس کے خارج کرے میں بے احتیاطی ایک عالمگیر نا پسندیدگی شمار ہوتی ہے.پس
اسلام نے بھی اس نا پسندیدگی کو قائم رکھا ہے اور اسے ناقض وضو قرار دیکہ احتیاط کی ترغیب
دی ہے تاکہ لازمی اجتماعات اور مجالس میں طبعی بدمزگی اور ذہنی تنفر پیدا کرنے والے اسباب
کی روک تھام ہو سکے.اور اجتماعات میں تنفر والی اور بو پھیلانے والی کوئی بات پیدا
نہ ہو.سوال :.نماز پڑھتے ہوئے اگر وضو ٹوٹ جائے تو کیا کیا جائے ؟
جواب:- نماز پڑھتے ہوئے اگر وضو ٹوٹ جائے تو دو صورتوں میں سے کوئی سی صورت اختیار
کی جاسکتی ہے.
Page 66
1- نماز چھوڑ کر جا کر دھو کرے اور پھر نئے سرے سے وہ ساری نماز پڑھے جس میں وضو ٹوٹا
ہے یہ صورت بہتر ہے.ب.بغیر کسی سے بات کئے اور زیادہ دیر لگائے جا کر وضو کرے اور پھر واپس آکر وہاں
سے نماز شروع کرے جہاں سے وہ چھوڑ گیا ہے.یہ صورت جائز ہے.ج - اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے اور وضو کر کے واپس آکر جماعت میں شامل
ہوا ہے تو جو رکھتیں امام اس دوران میں پڑھ چکا ہے وہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد اُٹھ کر پڑھ
سے یہ اس کی وہی رکھتیں ہونگی جو امام کے ساتھ پڑھنے سے رہ گئی ہیں.د - اگر امام نے ابھی پوری رکعت نہیں پڑھی صرف رکوع یا سجدہ میں گیا ہے تو جلدی سے
اپنے طور پر یہ رہا ہوا رکوع یا سجدہ کر کے امام کے ساتھ شامل ہو جائے.ابن ماجہ کی حدیث جیسے حضرت عائشہ اور حضرت ابو سعید خدری نے روایت کیا ہے
اس کے الفاظ یہ ہیں :-
من اصابة تى او رعاف اوقلس اومدى تلينصرت فليتوضا
ثم ليبن على صلوته دهو في ذالك لا يتكلم.(ابن ماجه كتاب الصلوة )
یعنی اگر کسی کو نماز میں تھے آ جائے یا نکسیر پھوٹ پڑے یا مذی کا قطرہ نکل
آئے تو وہ کسی سے بولے بغیر جاکر وضو کرے اور پھر اپنی پہلی نماز پر بنا
کرے یعنی جہاں سے نمازنہ چھوڑی ہے وہیں سے شروع کرے.اس
کی تشریح میں علماء نے لکھا ہے کہ
اجمع الخلفاء الراشدون وغيرهم كعبد الله بن مسعود د
عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر و انس بن مالک و سلمان
الفارسی رضی الله عنهم على ذالك -
رعمدة الرعاية لمولوى عبدالحی لکھنوی)
یعنی خلفاء راشدین اور بعض دوسرے اجل صحابہ مثلاً عبداللہ بن مسعود
عبداللہ بن عباس عبدالله بن عمر انس بن مالک اور مسلمان فارسی رضی الله عنهم
نے بھی اسی رائے سے اتفاق کیا ہے اور بنا کو جائز
ردیا ہے
Page 67
41
۱۸۷
حضرت امام البوحنیفہ اور امام مالک کا بھی یہی مذہب ہے.دنیل الاوطار )
یہی اصول نماز کے دوران میں قریباً تمام بھولوں کا ہے.مثلاً اگر کوئی بھول کر چار رکعت پڑھنے
کی بجائے دو رکعت پڑھ کر سلام پھیر دے اور پھر یاد آئے کہ اس نے تو صرف
دو رکعتیں پڑھی ہیں تو سلام
پھیر نے اور کسی سے بات کر لینے کے باوجود وہ صرف بقیہ دو رکعت ہی پڑھے گا اور آخر میں سجدہ سہو
کر گیا اس کے لیے نئے سرے سے چار رکعتیں پڑھنی ضروری نہیں.ایسا ہی اگر امام کا وضو ٹوٹ جائے
تو وہ کسی اور کو اپنی جگہ امام نا کر خود وضو کرنے چلا جائے اور بقیہ نماز بطور مقتدی کے اس دوسرے
امام کے پیچھے پڑھے.اگر وضو ٹوٹتے ہی اس کی نماز بھی ٹوٹ جائے تو پھر تو سارے مقتدیوں کی نماز
بھی ختم ہوئی کیونکہ ان کی نماز کی بنیاد امام کی نماز پر ہے.اسی طرح کسی حدیث یا فقہ کی کتاب میں یہ
نہیں لکھا کہ یہ امام اگر وضو کرکے اور مقر کردہ امام کا مقتدی بن کر جماعت میں شامل ہو جائے تو وہ
ان رکعتوں کو دوبارہ پڑھے جو وضو ٹوٹنے سے پہلے وہ پڑھ چکا تھا.پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
حادیثت خلفاء راشدین اور آپ کے صحابہ کے عمل ائمہ فقہ کے اجتہا دار عام اصولِ شرعیہ کے مد نظر یہی
صحیح ہے کہ وضو کر کے آنے کے بعد انسان اپنی نمازو میں سے شروع کر سکتا ہے جہاں سے وہ چھوڑ
کر گیا تھا.ہاں اگر کوئی اختیاط کے پیش نظر نئے سرے نماز پڑھ لے تو اس میں بھی کوئی حرج
نہیں بلکہ یہ ایک محتاط طریق ہو گا.سوال پر شدید سردی کی بنا پر کیا غسل جنابت کئے بغیر تیم سے نماز فجرادا کی جاسکتی ہے یا نہیں.جواب : اگر کسی مرد یا عورت کے لیے بوجہ جنابت نہانا ضروری ہو لیکن شدید سردی یاکسی اور عذر کی وجہ
سے نمایا نہ جا سکتا ہو تو تمیم کر کے نماز پڑھنا جائز ہے بشرطیکہ عذر صحیح اور معقول ہو اور نہانے کے لیے
گرم پانی کا بآسانی انتظام نہ ہو سکتا ہو یا کوئی اور معقول وجہ موجود ہو.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد
مبارک میں مشہور صحابی حضرت عمرو بن العاص کو ایک دفعہ ایسی ہی صورتِ حال کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں
نے تمیم کر کے نماز پڑھائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کا علم ہوا تو آپ نے نہ تو اس سے
منع فرمایا اور نہ ہی دوبارہ نماز پڑھنے کا حکم دیا حدیث کے الفاظ یہ ہیں :-
عن عمرو بن العاص انه لما بعث في غزوة ذات السلاسل
قال احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد نا شققت ان اغتسلت
ان اهلك فتيممت ثم صليت با صحابي صلاة الصبح قلما
قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ذالك فقال يا
Page 68
۶۲
عمر و صليت با صحابك وانت جنب فقلت ذكرت قول الله
تعالى ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما - نتيممت
ثم صليت نضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم
يقل شيئاً - رستن ابو داؤد باب الجنب، يتيم لحوق البرد)
ترحمه :-
حضرت عمرو بن العاص بیان کرتے ہیں کہ انہیں غزوہ ذات السلاسل میں امیر لشکر
بنا کر بھیجا گیا وہ کہتے ہیں کہ ایک رات انہیں احتلام ہو گیا سردی بڑی سخت تھی
اور نہانے سے شدید بیمار ہونے یا جان جانے کا خطرہ تھا تو میں نے تمیم کر کے
صبح کی نماز پڑھائی جب ہم واپس مدینہ آئے تو بعض سپاہیوں نے آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعہ کا ذکر کیا.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے
پوچھا اسے عمرہ تو نے حالت جنابت میں نماز پڑھائی تو میں نے عرض کیا کہ میں نے
تیم کیا تھا.نہانے کی بجائے تمیم کا جواز الہ تعالی کے اس قول سے مستنبط کیا
تھا کہ تم اپنے آپ کو تل کرو اللہ تعالی تم پر رحم کرنے والا اور مہربان ہے حضور
صلی اللہ علیہ وسلم یہ جواب سن کر منہس پڑے آپ نے
کسی قسم کی ناراضگی کا اظہار
ند فرمایا.اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے علامہ شوکانی لکھتے ہیں :-
تد استدل بهذا الحديث الشورى ومالك والبوذيفه و
ابن المنذر على ان من تيمم لشدة البرد وصلى لا يجب عليه الاعادة
لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يامره بالاعادة ولو كانت
واجبة لامرها بها ولانه أتى بما امر به وقدر عليه ناشيه
سائر من يصلى بالتيمم
۲۵۸
رنيل الأوطار ٣ )
یعنی اس حدیث سے حضرت امام ثوری امام مالک امام ابو حنیفہ اور امام
منذر وغیرہ نے یہ استدلال کیا ہے کہ جو شخص سخت سردی کی وجہ سے نہانے کی
بجائے تیمیم کر کے نماز پڑھ لیتا ہے اس کے لیے دوبارہ نماز پڑھنا ضروری نہیں
Page 69
کیونکہ آنحضت صلی الہ علیہ سلم نے حضرت عمر بن العاص کو دوبارہ نماز پڑھنے کا کم نہیں دیا
تھا اگر دوبارہ نماز پڑھنا ضروری ہوتا تو آپ انہیں ضرور حکم دیتے بس حضرت عمر نے جو
کہا وہ شریعیت کے مطابق تھا اس لیے جس طرح دوسرے عذر کی وجہ سے تمیم کرنے والا نماز
پڑھ سکتا ہے اس طرح حضرت عمرو نے بھی تمیم کر کے نماز پڑھی؟
سوال :.کیا نسل جنابت کے لیے عورت اپنے گوندھے ہوئے بال کھولکر دھوئے یا سر پر مسح کرے.جواب:.سر کے گوندھے ہوئے بال کھولنے اور دھونے ضروری نہیں صرف مسح کے رنگ میں تین چلو
پانی ڈالنا اور سر پر ہاتھ پھیرنا کافی ہے.حدیث میں آتا ہے.عن ام سلمة قالت يا رسول الله انى امراءة اشدُّ ضُفر رأسى
افالقضة لغسل الجنابة قال لا انما يكفيك ان تحتى على
رأسك ثلاث حثيات من ماء ثم تفيضى على سائر جدك
ر ترمذی باب غسل الجنابة 14 )
الماء فتطهرين.ترجمہ : حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ میںنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ میں مینڈھیاں
مضبوطی سے باندھتی ہوں کیا غسل جنابت کے لیے ان کو کھولنا ضروری ہے.حضور نے
فرمایا اس کی ضرورت نہیں.تین چلو پانی (مسیح کے رنگ میں اوپر ڈالنا کافی ہے اس
کے بعد سارے جسم پر پانی ڈال لو تو تم پاک ہو جاؤ گی.سوال پر اگر عورت چالیس روز سے پہلے نفاس سے پاک ہو جائے تو کیا وہ صوم وصلواۃ کی پابند قرار دی جاکتی
دہ
ہے یا ہر صورت مدت مقررہ یعنی چالیس روز پورے کرنے ضروری ہیں ؟
جواب :.چالیس روز سے پہلے اگر عورت نفاس سے پاک ہو جائے تو نہا کر عبادت بجالا سکتی ہے، چاہیں
دن پورے کرنا ضروری نہیں.الفضل ۱۹ راگست ۱۹۱۶ )
نماز ہر حال میں ضروری ہے خواہ بدن پر گند ہی کیوے نہ لگا ہو
سوال : ایک مخدوم غیر احمد نے دریافت کیاکہ میرا بدن پیل رہا ہے بار باریک نہیں کرسکا تو کیا ہے وی پڑھ لوں ؟
جواب : - صرف تمیم کریں اگر ظاہری نجاست ہو تو بشرط امکان اسکا ازالہ کریں اور لیس - (الفضل ۲۹ را پریل فواد )
کوئی ناپاک نہیں ہوتا.خدا تعالیٰ کا حکم ہے کہ بار مجبوری ناپاک حالت میں بھی نماز پڑھے.نماز پھر بھی جائز
ہے خواہ آپ سید سے بھرے ہوئے ہوں تب بھی نماز پڑھنے کیونکہ آپ اپنی خوشی سے تو ایسا نہیں کرتے ہاں جتنی
طهارت ممکن ہو کریں.باقی مجبوری امر ہے نماز پڑھیں نمازہ نہ چھوڑیں.(فائل مسائل دینی ۸-۳۲)
Page 70
۶۴
نماز کی تعمیری شرط
ستر عورت یعنی پردہ پوشی
لیاس سے بھی انسان معز لگتا ہے اس لیے پاک صاف
اور ستھرا لباس پہینکر انسان خدا کے دربار
میں جائے اور اس کے حضور نماز ادا کرے.گندے کپڑوں میں نماز نہیں ہوتی.مرد کے لیے کم از کم ناف
سے لے کر گھٹنوں تک کے جسم کی پردہ پوشی ضروری ہے ورنہ نماز صحیح نہ ہو گی.عورت نماز پڑھتے وقت
صرف چہرہ بشرطیکہ وہاں کوئی نامحرم موجود نہ ہو پہنچوں تک ہاتھ اور ٹخنوں تک پاؤں تنگے اور کھلے باہر
،
رکھ سکتی ہے اس کے بال با ہیں اور پنڈلیاں اور جسم کا باقی حصہ پردہ میں اور ڈھکا ہوا ہونا چاہیئے
اور
باریک کپڑا جس سے جسم نظر آئے نماز پڑھتے وقت نہیں پہننا چاہئیے.لباس کھلا کھلا سلا ہوا ہونا چاہیئے
تنگ اور چست لباس جس سے سجدہ کرنے یا بیٹھنے میں سخت وقت ہو نا پسندیدہ سمجھا گیا ہے اس طرح
نگے سرنماز پڑھنا یا سر پر تولیہ یا ڈال ڈال لینا یا چادر اس طرح اوڑھ لینا کہ ہاتھ اوپر اٹھاتے وقت
سنتر کے کھل جانے کا اندیشہ ہو اچھا نہیں سمجھا گیا.لباس کے متعلق عام ہدایت یہ ہے کہ مرد ریشمی لباس نہ پہنیں اورنہ ہی ایسا فاخرانہ اور کھڑکیا
لباس جو سب میں نمایاں کئے رکھے اور اوچھے پین پر دلالت کرے.ہمیشہ ستر کے مقصد کو پورا کرنے والا
با وقار اور سادہ لباس پہننا چاہیے.گر کسی شخص کے کپڑے ناپاک ہوں ان پر نجاست لگی ہوئی ہو اور اس کے پاس اور کپڑے نہ ہوں جو
بدل سکے اور نماز کا وقت آجائے تو انہی گندے کپڑوں کے ساتھ وہ نماز پڑھ سکتا ہے اگر پردہ ہے
تو کپڑے اتار کر لگے جسم کے ساتھ نماز پڑھ لے اور یہ پرواہ نہ کرے کہ اس کے کپڑے پاک نہیں میں
یا جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہے کیونکہ کپڑوں کی پاکندگی سے دل کی پاکیزگی ہر حال مقدم ہے پس یہ کیسے
Page 71
۶۵
جائز ہوسکتا ہے کہ کپڑوں کی ناپاکی کے خیال سے اپنے دل کو نا پاک کر لیا جائے اور اس بہانہ سے نماز ترک کردی
جائے لیا
ستر عورت
کوال : فکر بین کر نماز پڑھنے کے بارے میں کیا حکم ہے ؟
جواب : اگر کسی کے پاس نظر ہے اور دوسرا کپڑا نہیں تو نکر پہن کر جائز ہے بلکہ اگر اس کے پاس کپڑا نہیں
تو نکر چھوڑ لنگوٹی میں بھی نماز جائز ہے لیکن جان بوجھ کر ایسا کرنا جبکہ اور کپڑا موجود ہونا جائز ہے.الفضل ۱۷ اکتوبر ۱۹۴۶
سوال :.کیا عورت باریک دو پڑ جس میں بال نظر آئیں اوڑھ کر نماز پڑھ سکتی ہے.جواب:- ایسے باریک دوپٹے جن میں سے بال نظر آئیں اوڑھ کر نماز ادا کرنا درست نہیں.خصوصاً
ایسی جگہوں میں جاب غیر محرموں کی آمد ورفت ہو حضرت عائشہ سے حدیث مروی ہے کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-
لا يقبل الله صلوة حائض (اى امرأة ) الا بغمار -
ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا :.( بخاری )
لا يقبل الله من امرأة صلوة حتى توارى زينتها ولا جارية
بلغت المحيض حتى تختمر
( رواه طيراني عن ابی قتاده)
ان احادیث اور آیات قرآنی خذوا زينتكم عند كل مسجد اور دليفرين
بغمر هن على جيوبهن ولا بيدين زينتهن.....ولا يضربن بارجلهن
ليعلم ما يخفين من زينتهن
سے فقہاء نے مندرجہ ذیل استدلال کیا ہے.امام شافعی اور اوزاعی فرماتے ہیں :-
تخطى جميع بدنها الا وجهها وكفيها
تفسیر کبیره پنجم حصہ سوم صفحه ۲۳۱ تا ۲۴۲
Page 72
امام مالک فرماتے ہیں.اذا صلت المرأة وقد انكشف شعرها او ظهور قدميها
تعید ما دامت فی الوقت - لیکن صحیح مسلک یہ ہے کہ نماز میں سر کے بالوں
کو حتی الوسع چھپائے
رکھو اور اگر بغیر ارادہ کے بالوں کا کچھ حصہ کھل جائے تو نماز صحیح ہو جائے گی.پس جہاں
یہ تنگ نظری ہے کہ اگر ایک بال بھی کھل جائے تو نماز باطل ہو جائے گی وہاں یہ
بھی ناجائز اقدام ہے کہ ایسا دوپٹہ لیکر نماز پڑھی جائے کہ میں میں سے سر کے بال صاف دکھائی
دیں.مومن کا اصل کام یہ ہے کہ افراط اور تفریط دونوں سے نیچے.اسلام نے یہ پسند کیا ہے کہ نماز وغیرہ کے مواقع پر سر پر ٹوپی یا پگڑی رکھی جائے.سرنگا نہ
ہو.عورتوں کے متعلق علماء میں یہ اختلاف پایا جاتا ہے کہ اگر ان کے سر کے اگلے بال نگے ہوں تو
آیا ان
کی نماز ہو جاتی ہے یا نہیں.پرانے فقہاء کا خیال ہے کہ ننگے سرمرد کی نماز بھی نہیں ہوتی لیکن ہمارے ہاں مسائل کی بنیاد
چونکہ احادیث پر ہے اور احادیث میں ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ بعض صحابہ نے نگے سر نماز پڑھی اس لیے
ہم اس تشدد کے قائل نہیں کہ تنگے سر نمازہ ہوتی ہی نہیں ہمارے نزدیک اگر کسی کے پاس ٹوپی یا
گھڑی نہ ہو اسی طرح سرڈھانکنے کے لیے کوئی رومال وغیرہ بھی اس کے پاس نہ ہو تو نگے سرنماز پڑھی
جاسکتی ہے.البتہ عورتوں کے لیے دوپٹہ کا ہونا ضروری ہے.الفضل 9 فروری ۱۹۵۵ئه )
سوال:.کیا ننگے سر نماز جائز ہے ؟
جواب:.ایسی صورت میں ننگے سر نماز پڑھنا غلطی ہے جبکہ سرڈھانپنے کے لیے کوئی کپڑا وغیرہ
موجود ہو.منع نہیں کئی صحابہ پڑھتے تھے مگر میرا خیال ہے کہ ان کے پاس سر ڈھانکنے کے لیے
کپڑا نہیں ہوتا تھا.حدیثوں میں آتا ہے کہ صحابیہ کے پاس بسا اوقات تہبند کے لیے بھی پورا کپڑا
نہیں ہوتا تھا.الفضل ۱۷ اکتوبر ۱۹۴۶ء
سوال:- اگر صاف اور پاک کپڑا نہ ملے تو کیا کرے ؟
جواب: اگر کسی کو صاف اور پاک کپڑا میسر نہ آئے تو وہ گندے کپڑوں میں ہی نماز پڑھ
سکتا ہے خصوصاً وہم کی بناء پر نماز کا ترک تو بالکل غیر معقول ہے جیسا کہ ہمارے ملک
میں کئی عورتیں اس وجہ سے نمازہ ترک کر دیتی ہیں کہ بچوں کی وجہ سے کپڑے مشتبہہ ہیں اور
Page 73
46
کئی مسافر نماز ترک کر دیتے ہیں کہ سفر میں طہارت کامل نہیں ہو سکتی.یہ سب شیطانی وسادس ہیں.لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً
کے ترک میں گناہ ہے.الا
وسعها
الٹی حکم ہے جب تک شرائط کا پورا کرنا اختیار میں ہو ان
لیکن جب شرائط پوری کی ہی نہ جاسکتی ہوں یا ان پورا کرنا مشکل ہو تو ان کے میسر نہ آنے کی وجہ سے
نماز کا ترک گناہ ہے اور ایسا شخص معذور نہیں بلکہ نماز کا تارک سمجھا جائے گا.( تفسير كبير جلد ۱ صفحه ۱۰۴)
Page 74
نماز کی پوتھی شرط
۶۸
نماز میں قبلہ کی طرف منہ کرنا ضروری ہے.قبلہ سے مراد وہ مقدس کمرہ ہے جو مکہ مکرمہ میں
موجود ہے جسے کعبہ اور بیت اللہ یعنی اللہ تعالی کا گھر بھی کہتے ہیں.پتھر کی بنی ہوئی یہ عمارت سیاہ
نزنگ کے ریشمی غلاف سے ڈھکی رہتی ہے.اس کی لمبائی ۲۴ فٹ چوڑائی ۳۳ فٹ اور اونچائی ۴۵
فٹ کے قریب ہے.اس کا دروازہ زمین سے سات فٹ بلند ہے اور چاہ زمزم کی طرف کھلتا ہے.اس کے اردگر د گول دائرہ کی شکل میں ایک وسیع مسجد ہے جسے المسجد الحرام کہتے ہیں.دنیا کی تمام
مساجد اسی مسجد کے تابع اور اس کا ظل ہیں.بیت اللہ سے یہ مراد نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ اس
مکان میں رہتا ہے.وہ تو لا مکاں اور گھر کی احتیاج سے منزہ اور پاک ہے بلکہ اس مقدس کمرہ کو
بیت اللہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب سے مذہب کی ابتداء ہوئی دنیا میں یہ پہلی عمارت ہے جو
خالص اللہ تعالٰی کی عبادت کی خاطر بنائی گئی.روایت ہے کہ یہ مقدس عمارت تمام انبیاء کا قبلہ رہی
حضرت آدم علیہ السلام اور دوسرے انبیاء نے اس کا نتیج کیا.حضرت ابراہیم علیہ اسلام سے پہلے
کسی وقت یہ عمارت منہدم ہوگئی اور اس کے اردگرد جو آبادی تھی وہ بھی اجڑ گئی.اللہ تعالیٰ کی طرف سے
اشارہ پا کر حضرت ابراہیم علیہ اسلام نے اپنے پلوٹھے بیٹے حضرت اسمعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضر
ہاجرہ کو اس جگہ لا بسایا اور بالہام الہی باپ بیٹے دونوں نے مل کر یہ مقدس عمارت اپنی پہلی بنیادوں
پر دوبارہ تعمیر کی.اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اب تک آباد ہے.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں رہے اس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے رہے.مدینہ میں ہجرت کہ آنے کے بعد چند ماہ بیت المقدس دواقعہ فلسطین کی طرف آپ نے منہ کیا اس کے
بعد اللہ تعالیٰ نے مستقل طور پر کعبہ کی طرف منہ کرنے کا آپ
کو حکم دیا.کیونکہ الہ تعالیٰ کے وعدوں کے
مطابق اسی مقدس مکان نے ہمیشہ ہمیش کے لئے عبادت انہی کا دائمی مرکزہ مسلمانان عالم کی توجہات کا
مرجع اور ان کے اجتماع و اتحاد کا مقدس نشان بننا تھا.چنانچہ اس وقت سے یہ مقدس گھر مسلمانوں کا
دائمی قبلہ ہے اور حکم الہی نا روز قیامت امت مسلمہ کا قبلہ رہے گا.زادھا اللہ شرفا وعظمة -
ه آل عمران : ۹۶ : سه طبری تاریخ الوفاء ۱ : ۳ بحواله الفضل ۲۳ را پریل مستشار به : - بقه : ۱۲۶
Page 75
49
جو لوگ مسجد حرام میں نماز ادا کرتے ہیں یا کعبتہ اللہ انہیں نظر آتا ہے وہ نماز میں سیدھے ان
کعبہ اللہ کی طرف منہ کریں.یہی وجہ ہے کہ مسجد حرام میں کعبہ کے اردگرد نماز کی صفین گول دائرہ
کی شکل میں ہوتی ہیں.جن لوگوں
کو کعبہ کی عمارت نظر نہیں آتی.وہ دُور ہیں یا دوسرے ممالک میں رہتے
ہیں اُن کا قبلہ کعبہ اور مسجد جہام کی جہت ہے اُن کے لئے عین عمارت کعبہ کی طرف منہ کرنا ضر ہے
نہیں اور نہ ہی آسانی سے ایسا کرناممکن ہی ہے.خوف کی حالت ہو یا انسان کسی ایسی سواری پر سفر
کر رہا ہو جسے ٹھہرانا اس کے اپنے اختیار میں نہیں یا ٹھہرانا موجب حرج ہے اور چلتے ہوئے شیح
قبلہ کی طرف منہ کرنا خاصہ مشکل ہے یا سفر ہوائی جہاز کا ہے یا کسی دوسرے سیارہ میں انسان
جارہا ہے ایسی تمام صورتوں میں جدھر آسانی ہو اس طرف منہ کر کے نما نہ پڑھ لینا جائز ہے لیے یہی
جہت اُس کے لئے بمنزلہ قبلہ متصور ہوگی.اسی طرح اگر سواری میں بیٹھے بیٹھے قبلہ کی طرف منہ کر کے
نماز شروع کی اور سواری کے چلنے کی وجہ سے اُس کا منہ کسی اور طرف ہو گیا تو اس سے نمازہ کی صحت
پر کوئی اثر نہیں پڑے گا.اگر جہت قبلہ کا پتہ نہیں چلتا اور کوئی ایسا شخص بھی موجود نہیں جس سے
پوچھا جا سکے تو اپنی سمجھ اور علم کے مطابق جدھر خیال جائے کہ قبلہ اس طرف ہے ادھر ہی منہ
کر کے نماز پڑھ لی جائے.پھر اگر نماز کے دوران میں پتہ لگ جائے کہ غلط جہت کی طرف منہ ہے تو
نماز میں ہی صحیح جہت کی طرف منہ کر لیا جائے اور اگر نماز سے فارغ ہونے کے بعد اس غلطی کا پتہ
چلے تو پھر دوبارہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں کیونکہ انسان نے اپنی سمجھ کے مطابق عمل کیا اس لئے جو
نمانہ اس نے پڑھی وہ صحیح ہے.کعبہ کی عمارت کے اندر فرض نماز پڑھنے یا اس کی چھت پر نماز پڑھنے
کی کوئی سند نہیں ملتی.اس لئے اسے جائز نہیں سمجھا گیا.قبلہ کی حکمت
نماز میں کعبہ کی طرف منہ کر نے کے یہ معنے نہیں کہ مسلمان نعوذ باللہ اس عمارت کی پرستش کرتے
ہیں اور اُسے پوجتے ہیں.مسلمان تو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں صرف اسی کو اپنا کارسانہ
اور خالق و مالک مانتے ہیں.در اصل کعبہ کو قبلہ مقرر کر نے میں یہ حکمت ہے کہ نماز ایک مخصوص اجتماعی عبادت ہے جس
میں یک جہتی اور اتحاد عمل کو خاص طور پر ملحوظ رکھا گیا ہے تاکہ سب کی توجہ ایک طرف رہے.اس
لئے عام حالات میں نماز پڑھنے کے وقت اس مقام کو سمت اور قبلہ مقرر کیا گیا جسے توحید الہی کیلئے
:- بقره : ۱۱۵
Page 76
پہلا اور اصلی مرکز ہونے کا شرف حاصل ہوا.جہاں خداوند تعالیٰ کی وحدایت کے گیت گائے گئے
جہاں سے تبلیغ توحید کا آغاز ہوا.اور جس جگہ ایسی قربانیاں دی گئیں جو تاریخ عالم میں بے مثال
ہیں.جہاں کا چپہ چپہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے عطر سے مسورج ہے جو مقام شعائر اللہ سے معمور ہے اور
ان شعائر میں ایک مقام وہ بھی ہے جسے بیت اللہ ہونے کا منفر د شرف حاصل ہے اور توحید
في العبادت کا عظیم الشان نشان ہے.مسلمانان عالم دن میں کم از کم پانچ بار اسی ایک سمیت کی
طرف منہ کرتے ہیں جس سے عالمگیر یک جہتی اور اتحاد انسانیت کا خیال افروز اور حسین تصویر
ساری دنیا کو عطا کیا گیا ہے :
Page 77
نماز کی پانچویں شرط
J
صحت نماز کے لئے نیت بھی ضروری ہے.نیت کے معنے ارادہ کے ہیں.نماز شروع کرتے
وقت دل میں یہ ارادہ ہونا چاہیے کہ وہ کسی وقت کی اور کونسی نماز پڑھ رہا ہے.کیونکہ میں نمازہ کی
نیت ہوگی وہی نماز اس کی ہوگی.ظہر کے وقت اگر نیت یہ ہے کہ چار رکعت فرض شروع کرنے
لگا ہے تو فرض نماز ہوگی.اگر نیت چار رکعت یا دو رکعت سنت کی ہے تو سنت نماز ہوگی.اگر
نیت نقل کی ہے تو نفل اور اگر نیست عصر کی فرض نماز اور جمع کرنے کی ہے تو اس کے مطابق اس کی
نماز ادا ہوگی.غرض نیت کے بدلنے سے نماز کی نوعیت بدل جائے گی.نیت کا تعلق دل سے ہے اس لئے دل میں یہ طے ہونا چاہیے کہ وہ کس وقت کی اور کتنی رکعت
نماز شروع کرنے لگا ہے.منہ سے نیت کے الفاظ ادا کرنے ضروری نہیں.بلکہ بعض صورتوں میں تو
منہ سے اظہار نیت کے الفاظ نکالنے کو مستحسن بھی نہیں سمجھا گیا.نیست میں خلوص کا مفہوم بھی موجود ہے.اگر انسان خدا کی خاطر نماز پڑھے گا تو اس کی نماز خدا
کے حضور مقبول ہوگی اور اگر وہ دکھاو سے یا کسی اور کے ڈر سے یا خوش کرنے کے لئے نماز
پڑھے گا تو خدا تعالیٰ کے دربار سے اُسے کچھ نہیں لے گا.الغرض تمام دینی اعمال کا دار دیدار ظاہراً
و باطنا نیت پر ہے اس لئے خُدا تعالیٰ کے حضور ہر ایک کے اعمال اسی میزان کے مطابق تئیں گے
اور ہر ایک اسی کے مطابق بدلہ پائے گا :
Page 78
جز وسوم
اسلامی نماز
نماز پڑھنے کا طریق
اسلام میں نماز کی جو صورت متعین ہوئی ہے اُس سے بڑھ کر مقبول و متبوع صورت
نہ تو کسی اور
مذہب میں رائج ہے اور نہ ہی اس سے بہتر عقل میں آسکتی ہے.یہ جامع اور مانع طریق ان تمام
عمدہ اصولوں اور مسلمہ خوبیوں اور فطری استعدادوں پر حاوی ہے جو دنیا کے اور مذاہب میں فرداً فرداً
موجود ہیں.اور نیاز مندی کے ان تمام آداب کو شامل ہے جو ذو الجلال معبود کے سامنے قوائے انسانی
میں پیدا ہو نے ممکن ہیں.اس طرح وہ خاص کلمات جو نماز میں صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے بھی
نکالے جاتے ہیں.اور جس روح انسانی متاثر ہوتی ہے نماز کی بے نظیری کے کافی ثبوت ہیں.طریق نماز
جو شخص نماز پڑھنے لگے وہ پاک بدن اور پاک لباس کے ساتھ جس وقت کی نماز پڑھنا چاہتا
ہے اس کی دل میں نیت کر کے قبلہ رو کھڑا ہو جائے.اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھ کانوں تک
اُٹھائے اور ساتھ ہی اللہ اکبر یعنی اللہ سب سے بڑا ہے کہے.اس تکبیر کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں پھر
اپنے ہاتھ سینہ کے نچلے حصہ کے قریب اس طرح باندھے کہ دایاں ہاتھ ادو پرا اور بایاں نیچے ہو.اس
طرح کھڑے ہونے کو قیام کہتے ہیں.اس کے بعد ثناء :-
سبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا
إله غيرُكَ " پڑھے یعنی اسے اللہ میں تجھے سب نقائص سے پاک مانتا ہوں
اور تیری حمد میں مشغول ہوں.برکت والا ہے تیرا نام اور بڑی ہے تیری شان نہیں ہے
کوئی قابل پرستش تیر سے سواک
Page 79
پھر تعوذ :-
اعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ پڑھے.یعنی میں اللہ تعالی کی پناہ مانگتا ہوں
دھتکار سے ہوئے شیطان سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے شیطانی حملوں سے محفوظ رکھے).اس کے بعد تسمیہ کمیت سورۂ فاتحہ پڑھے جو یہ ہے:.بِسمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ : مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ
إيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ : اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ هُ صِرَاطَ
الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالين آمين
ترجمہ : میں اللہ تعالٰی کا نام ہے کہ پڑھتا ہوں جو بے انتہا کرم کرنے والا اور بار بار رحم
کرنے والا ہے.تعریف توصیف اور حمد و ثناء کے لائق صرف اللہ تعالیٰ ہے جو تمام
جہانوں
کو پالنے والا.بے انتہا کرم کرنے والا.بار بار رحم کرنے والا ہے.جزا وسزا کے
دن کا مالک ہے را سے ان خوبیوں کے مالک خُدا ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور
تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں.تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا.اُن لوگوں کے راستہ پر جن
پر تو نے انعام کیا.یہ ایسے لوگ ہیں جن پر نہ تیرا غضب نازل ہوا اور نہ گمراہ ہوئے.اسے اللہ تو یہ دعا قبول فرما.سورۃ فاتحہ کے ساتھ قرآن کریم کی کوئی سورۃ یا کم سے کم سورۃ کا اتنا حصہ جو تین چھوٹی آیات پر
مشتمل ہو پڑھے.مثلاً سورۃ کوثر ہے :-
انا عطَيْنَكَ الْكَوْثَرَهُ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَالْحَرُهُ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُهُ
یقینا ہم نے تجھے کو ثر عطا کیا ہے سو تو اپنے رب کی عبادت کر اور اس کی خاطر قربانیاں کمر اور
یقین رکھ کہ تیرا مخالف ہی نرینہ اولاد سے محروم ثابت ہو گا.اس کے بعد تکبیر یعنی الہ اکبر کہ کہ رکوع میں چلا جائے اور اس طرح مجھے کہ پیٹھ اور سر موارد
ایک سیدھ میں ہوں.دایاں ہا تھے.دائیں گھٹنے پر اور بایاں ہا تھ بائیں گھٹنے پر رکھے.رکوع میں
کم از کم تین بار تسبیح سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِیم پڑھے یعنی پاک ہے تمام نقائص سے میرا
پروردگار عظیم قدرتوں والا.اور پھر تسمیع " سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَه ، یعنی سُنتا ہے
اللہ تعالی اس شخص کی جو اس کی حمد و ثنا کرتا ہے.کہتے ہوئے سیدھا کھڑا ہو جائے اس دوران
Page 80
۷۴
-
میں ہاتھ سیدھے چھوڑے رکھے.پھر تحمید ربنا وَ لَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كثيرًا طيبًا
مُبَارَ كَافِية - " پڑھے.یعنی اسے ہمارے رب تیرے لئے حمد وثنا ہے بہت حمد وثنا.پاکیزہ تم اس میں برکت ہی برکت ہے.پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اس طرح سجدہ کرے کہ گھٹنے ہا تھ ناک اور پیشانی زمین پر رکھ دے
سجدہ میں تین بار تسبیح " سُبحان ربي الأعلى" کہے.یعنی پاک ہے تمام نقائص سے میرا پروردگار
بلندشان والا.اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے اس طرح بیٹھے کہ بایاں پاؤں بجھا کر اس پر بیٹھے.اور دایاں پاؤں کھڑا نہ کھے جس کی انگلیاں قبلہ رخ ہوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھے اور دُعائے جلسہ :.اللهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَعَافِنِي وَارْفَتْنِي وَاجْبُرْنِي
وارزنی یعنی اسے میرے خُدا میرے گناہ بخش اور مجھ پر رحم فرما اور مجھے
"
ہدایت دے اور مجھے خیریت سے رکھ اور مجھے بلندی بخش اور مجھے رزق دیے " پڑھے.پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ کر ہے.اور اس میں بھی کم از کم تین با تسبیح سبحان ربی
الاعلیٰ" کہے.اس طرح اس کی ایک رکعت مکمل ہو جائے گی.اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری رکعت کے لئے کھڑا ہو جائے اور پہلے کی طرح دوسری
رکعت مکمل کرے.یعنی ہاتھ باندھ کر تسمیہ سمیت سورۃ فاتحہ پڑھے اور اس کے بعد قرآن کریم کا کوئی حصہ
پڑھے.مثلاً سورہ اخلاص پڑھے جو یہ ہے :
قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ : تو کہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں اکیلا ہے
اللهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ اللہ کے سب محتاج نہیں نہ اپنے کسی کو جینا ہے اور نہ وہ
يُولَدُهُ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا اَحَدُه جن گیا ہے اور اسی صفات میں کوئی بھی اسکا شریک کار نہیں ہے.اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے پہلے کی طرح رکوع و سجدہ کر ہے.اس طرح یہ اس کی دوسرا کوفت
مکمل ہو گئی.پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اس طرح بیٹھ جائے جس طرح وہ پہلا سجدہ کرنے کے بعد بیٹھا
تھا اور اس طرح بیٹھ کر تشہد پڑھے جو یہ ہے :-
التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَواتُ وَالطَّيِّبت تمام زبانی.بدنی اور مالی عبادتیں صر اللہ تعالی کے حضور میں
السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةٌ ہی بجالائی جاسکتی ہیں یہ پاکیزہ تعلیم دینے والے، اسے نبی
الله وبركاته السَّلَامُ عَلَينا و تجھ پر سلامتی ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اسکی برکات ہوں اور
على عِبَادِ اللهِ الصَّلِحِينَ یہ اعلی تعلیم قبول کرنے کی وجہ ہم پر بھی اور اللہ تعالے
Page 81
40
کے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو.اشْهَدُ أَنْ لا إلهَ إِلَّا اللهُ میں شہادت دیتا ہوں
کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور
وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ قابل پرستش نہیں اور وہ اپنی ذات میں اکیلا ہے
اشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ اور اسکا کوئی ہمسر نہیں ہیں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد
وَرَسُوله له
اُس کا ریولی اور بندہ ہے.( اور اس کے ذریعہ ہی یہ
اعلی تعلیم ہم تک پہنچی ہے.اگیر نماز صرف دو رکعت کی ہے تو یہ اس کا آخری قعدہ ہوگا اس لئے تشہد کے بعد
درود شریف پڑھے جب کسی الفاظ یہ ہیں :.اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ اسے میرے خدا تو اپنا خاص فضل نازل کو محمد پر
وَ عَلَى الِ مُحَمَّدِ كَمَا صَلَّيْتَ اور آل محمد یعنی آپ سے قریبی تعلق رکھنے والوں
على إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ پر جس طرح تو نے ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر
إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ - خاص فضل نازل کیا تو بے انتہا خوبیوں والا
اللهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ و بڑی شان والا ہے.اسے میرے خدا تو برکت
عَلَى آلِ مُحَمَّدِ كَمَا بَارَكنت نازل کر محمد پر اور آل محمد یعنی آپ سے قریبی
عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى ال تعلق رکھنے والوں پر جس طرح تو نے ابراہیم پچھ
إبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ اور آل ابراہیم پر خاص برکت نازل کی.یقیناً تو
بے انتہا خو بیوں والا اور بڑی شان والا ہے.پھر حسب پسند دعائیں کر ہے مثلاً : -
ربَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةُ اسے ہمارے رب دنیا میں بھی نہیں بھلائی
وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما.عَذَابَ النَّارِية
اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا.اس کے بعد دائیں طرف منہ پھیرتے ہوئے السّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ کہے یعنی
سلامتی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت تم پر نازل ہو.اسی طرح بائیں طرف منہ پھیرتے ہوئے السلام
عليكم ورحمة الله کہے.لیکن اگر اس کی نماز تین یا چار رکعت کی ہے تو یہ اس کا درمیانی
قعدہ ہو گا.اس لئے تشہد پڑھنے کے بعد درود شریف وغیرہ پڑھے بغیر اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑا ہو جائے.ه بخاری باب التشهد في الآخرة من مطبوعہ ہند کے سورة بقره ۲۰۱ :
Page 82
اور پہلے کی طرح جتنی رکعتوں کی نمازہ ہو اس کے مطابق پہلی دو رکعتوں کی طرح تیسری چوتھی رکعت
پڑھے.اگر یہ فرض نماز ہے تو تیسری یا چوتھی رکعت میں صرف سورۃ فاتحہ پڑھے.کوئی اور سورۃ
یا قرآن کریم کا کوئی حصہ نہ پڑھے.سورۃ فاتحہ کے بعد رکوع میں چلا جائے.اور اگر فرض نماز نہیں
بلکہ سنت - وتم یا نفل نماز ہے تو پھر تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد
قرآن کریم کا کوئی اور حصہ پڑھنا ضروری ہوگا.غرض اس طرح بقیہ رکعتیں پوری کر کے آخری تشہیر کے لئے بیٹھ جائے.تشہد پڑھے پھر
درود شریف اور حسب منشاء کوئی مسنون دُعا پڑھ کر دونوں طرف منہ پھیرتے ہوئے تسلیم
یعنی السلام عَلَيْكُمْ وَرَحْمَه الله کہے.نماز سے فارغ ہونے کے بعد تسبیح و تحمید کرنا
کچھ دیر تک ذکر الہی میں مشغول رہنا.مختلف دعائیں پڑھنا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے.جو شخص بیمار ہے اور کھڑا نہیں ہو سکتا وہ بیٹھ کر نماز پڑھے.اگر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو
لیٹ کر پڑھے اور اگر رکوع و سجدہ نہیں کر سکتا تو اشارہ سے رکوع وسجدہ کرے یعنی سر کو
جھکائے اور کچھ جنبش دے.اسی طرح اگر ریل گاڑی بائیس وغیرہ کی سواری پر سفر کر رہا ہے اور
کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا اور نہ ہی سواری کو ٹھہرا کر اتر کر نماز پڑھ سکتا ہے تو اس
صورت میں بھی بیٹھے بیٹھے نماز پڑھے اس عدد کی صورت میں قبلہ کی طرف منہ کرنا ضروری نہیں
ہوگا ہے
نماز میں ہاتھ باندھنا
اگرچہ
اگر چہ ہاتھ چھوڑ کر نمانہ پڑھنا کسی حدیث سے ثابت نہیں اور دست بستہ کھڑا
ہونا قانون فطرت کے گرد سے بھی بندگی کے لئے مناسب معلوم ہوتا ہے.لیکن
اگر ہا تھ چھوڑ کر بھی نماز پڑھتے ہیں تو نماز ہو جاتی ہے.مالکی بھی شیعوں کی طرح ہاتھ
چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں مسنون وہی طریق ہے جو اوپر بیان ہوا "
(فتاوی مسیح موعود من )
نماز میں ہاتھ باندھنے کے بارہ میں امام مالک اپنی مشہور کتاب موطا میں روایت کرتے ہیں :-
" عن عبد الكريم بن ابى المخارق البصرى انه قال من كلام النبوة
اذا لم تستحى ناصنع ما شئت ووضع اليدين احدهما على الأخرى
Page 83
في الصلوة اليمنى على اليسرى -
ر موطا امام مالک باب وضع اليدين او را هما على الاخرى في الصلواة مثل)
اسی طرح بخاری اور مسلم کی روایت ہے :-
عن سهل بن سعد الساعدي قد كان الناس يؤمرون ان يضع
الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى فى الصلاة -
د بخاری کتاب الاذان باب وضع الیمنی على اليسرى من جلد اول علم مصر )
سوال :.نماز میں ہاتھ باندھنے کا طریق کیا ہے ؟
جواب : " ہاتھ باندھنے کا اصل اور صحیح طریق یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کے انگوٹھے اور چھوٹی
انگلی سے بائیں ہاتھ کے پنجے کے قریب سے کلائی پکڑے اور دائیں ہاتھ کی باقی تین
اُنگلیاں لمبے رُخ بائیں ہاتھ کی کلائی پر رکھے " اے
رفع یدین
سوال : - اہل حدیث کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکرایہ اور حضرت عثمان نے آخر
تک نماز میں رفع یدین کرتے رہے.اس بارہ میں جماعت احمدیہ کا کیا مسلک ہے ؟
جواب : - نماز میں کس کس جگہ ہاتھ اُٹھائے جائیں اس بارہ میں اختلاف ہے.نماز شروع کرتے
وقت ہاتھ اٹھا نے یعنی رفع یدین کرنے کے بارہ میں تو تمام علماء کا اتفاق ہے اور صحیح احادیث
میں اس کا ذکر موجود ہے.لیکن اس کے علاوہ مندرجہ ذیل جگہوں میں اختلاف ہے.رکوع میں
جاتے ہوئے.رکوع سے اٹھتے ہوئے.سجدہ میں جاتے ہوئے سجدہ سے اٹھتے ہوئے.سجدہ کے بعد دوسری رکعت کے لئے اُٹھتے ہوئے.تشہد اول سے اُٹھتے ہوئے.آخری
تشہد کے بعد سلام کے وقت.غرض تکبیر تحریمہ کے علاوہ باقی سات جگہوں کے بارہ میں
مختلف احادیث میں ذکر آیا ہے جس میں سے چند یہ ہیں :-
ا - عن مالك بن حويرث انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع
يديه فى صلوته اذا ركع واذا رفع راسه من الركوع واذا سجد
و اذا رفع راسه من السجود - (نسائی)
یعنی مالک بن حویرث کہتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کے جب
: بهار شریعت ص
Page 84
۷۸
رکوع میں جاتے.جب رکوع سے اُٹھتے.جب سجدہ میں جاتے.جب سجدہ سے
اُٹھتے تو ہر موقع پر رفع یدین کرتے.اسی مفہوم کی احادیث ترمذی اور ابو داؤد میں
بھی مختصراً آئی ہیں.۲ - حضرت امام بخاری نے اپنے رسالہ رفع الیدین میں ابن عمر سے روایت کی ہے کہ آنحصر
صلی اللہ علیہ وسلم تشہد اول سے اُٹھتے ہوئے رفع یدین کیا کرتے تھے.اسی طرح ایک
روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشہد کے بعد سلام پھیر تے وقت.ہاتھ
اُٹھاتے تھے اس
قسم کی تمام احادیث کے باوجود اکثر اہل حدیث صرف تین موقعوں پر
رفع یدین کو تسلیم کرتے ہیں یعنی تکبیر تحریمہ کے وقت.رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع
سے سیدھا کھڑا ہونے پر.انہوں نے باقی احادیث کو نظر انداز کر دیا ہے.اس کے
بالمقابل بعض اور سائمہ نے جن میں امام ابو حنیفہ اور امام مالک بھی شامل ہیں صرف
شروع میں تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کو ضروری مانا ہے اور باقی جگہوں میں ہاتھ
اٹھانے سے منع کیا ہے ان ائمہ کا استدلال مندرجہ ذیل روایات سے ہے :-
، قال عبد الله ابن مسعود الا اصلی بكم صلوة رسول الله صلى الله
عليه وسلم فَصَلَّى ولم يرفع يديه الا اول مرة.یعنی مشہور صحابی حضرت عبد اللہ بن مسعود نے ایک بار کہا.کیا میں تمہیں نماز پڑھا کہ
نہ بتاؤں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح نما نہ پڑھا کرتے تھے.چنانچہ آپ نے
اس کے مطابق نماز پڑھائی اور اس میں صرف ایک بار تکبیر تحریمہ کے موقع پر )
ہاتھ اُٹھائے.یہ حدیث ترمذی نے بیان کی ہے جو صحاح ستہ میں شامل ہے.اسی طرح ابو داؤد اور نسائی
نے بھی اسے روایت کیا ہے.(۲) عن ابن مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع
يديه الأعند افتتاح الصلوة ولا يعود شيئًا من ذالك.یعنی ابن مسعود روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحر یر کے سوا نماز
کے کسی اور حصہ میں ہاتھ نہیں اُٹھاتے تھے.(مسند امام ابو حنیفہ)
الا
(۳) عن ابن مسعود قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
Page 85
و
وابى بكر و عمر فلم يرفعوا ايديهم الاعتد استفتاح
الصلوة
(بیہقی )
یعنی حضرت ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ، حضرت
ابو بکر حضرت عمران کے پیچھے نمازیں پڑھیں.تکبیر تحریمہ کے علاوہ یہ کسی موقع پر
رفع یدین نہیں کرتے تھے.(م) ابو اسحاق بیان کرتے ہیں.کان اصحاب عبدالله و اصحاب علی لا
يرفعون ايديهم الا في افتتاح الصلوة که حضرت عبد الله بن مسعود
اور حضرت علی کے ساتھی تکبیر تحریمہ کے علاوہ نماز کے کسی اور حصہ میں ہاتھ نہیں
اٹھایا کر تے تھے.(ه) قال النيحوى الصحابة رضى الله عنهم ومن بعدهم مختلفون
في هذا الباب واما الخلفاء الاربعة فلم يثبت عنهم رفع
الأيدى فى غير تكبيرة الإحرام
یعنی علامہ نیموی لکھتے ہیں کہ صحابہ رفع یدین کے بارہ میں مختلف الرائے تھے البتہ
خلفائے اربعہ کے بارہ میں کسی صحیح روایت سے ثابت نہیں کہ وہ تکبیر تحریمہ کے علاوہ
بھی رفع یدین کرتے تھے.(4) عن ابن عباس انه قال العشرة الذين شهد لهم رسول الله
عليه وسلم بالجنة ما كانوا يرفعون ايديهم الآني انتتاح
الصلوة -
یعنی حضرت ابن عباس کا بیان ہے کہ عشرہ مبشرہ میں سے کوئی بھی تکبیر تحریمہ کے
موقع کے علاوہ رفع یدین نہیں کرتا تھا.ان روایات سے ظاہر ہے کہ اس بارہ میں شروع سے اختلاف چلا آرہا ہے.بعض روایات سے
تکبیر تحریمیر کے علاوہ بھی رفع یدین ثابت ہے اور بعض سے اس کی تردید ثابت ہوتی ہے.پھر جو دوسرے
مواقع پر رفع یدین کے قائل ہیں وہ بھی ساری احادیث پر عمل نہیں کرتے.بعض بیان کا عمل ہے اور
بعض کو انہوں نے متروک العمل پایا ہے.ایسے حالات میں فقہ کے اولین ائمہ مثلاً امام اعظم ابوحنیفہ
امام دارالہجرت مالک.امام ثوری کی رائے کو خاص اہمیت حاصل ہوتی چاہیئے.کیونکہ انہوں نے
Page 86
صحابہ کے قریب کا زمانہ پایا خصوصا امام مالک تو مدینہ کے رہنے والے تھے اور اہل مدینہ کا دستور العمل
جو صحابہ کے اتنے قریب کا دور تھا اُن کے سامنے تھا.یہ سب جب عملاً رفع یدین کے اس رنگ
میں قائل نہیں تو اس کا صاف مطلب ہے کہ اس بارہ میں ضرور کوئی تبدیلی واقع ہوئی ہے اور ترک
رفع بدین کی روایات بے بنیاد نہیں ہیں.مالکیوں کی فقہ کی مشہور کتاب مدونة الكبرى میں ہے :-
قال مالك لا اعرن رفع اليدين في شيء من تكبير الصلوة لاني
خفض ولا في رفع الا فى افتتاح الصلوة -
ا وجز المسالک شرح موطا امام مالک ص۲۳)
یعنی امام مالک کہتے تھے کہ تکبیر تحریمیہ کے علاوہ نماز کے کسی اور حصہ میں رفع یدین کے بارہ
میں میرا کوئی مشاہدہ نہیں ہے گویا آپ کے زمانہ میں اہالیان مدینہ میں اس طرح رفع یدین
کا دستور نہ تھا.پس مذکورہ تصریحات کی روشنی میں یہ کہنا کیونکہ جائزہ ہو سکتا ہے کہ پہلی
بار کے علاوہ دوسرے مواقع پہ رفع یدین نہ کرنے والے تارک السنت ہیں.اس زمانہ کے حکم و عدل سید نا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس نزاع کا یوں حل فرمایا کہ دونوں
فریق نے اس بارہ میں شدت اختیار کی ہے اور جو لوگ یرفع یدین کے قائل نہیں ہیں ان کی روایات کو
ضعیف اور بے بنیاد قرار دینا بھی قرین انصاف نہیں.چنانچہ آپ فرماتے ہیں :-
" اس میں دیعنی رفع یدین میں چنداں حرج نہیں معلوم ہوتا خواہ کوئی کرے یا نہ کرے.احادیث میں بھی اس کا ذکر دونوں طرح پر ہے.معلوم ہوتا ہے رسول اللہ صلی الہ علیہ وسلم
نے کسی وقت رفع یدین کیا بعد انساں ترک کر دیا " نے
ایک اور موقع پر فرمایا : -
ضروری نہیں اور جو کمر سے تو جائز ہے؟
سوال :.نمازہ میں دو سجد سے اور ایک رکوخ کیوں کرتے ہیں ؟
جواب :.اس استفسار کا اصولی جواب تو یہ ہے کہ اللہ تعالٰی نے ایسا ہی حکم دیا ہے اور فروعی
احکام کی حکمتوں کے معلوم کرنے کے ہم مکلف نہیں ہیں.اس کی بالکل ایسی ہی مثال ہے
جیسے ایک شخص کی قابلیت اس کی صلاحیت اور اس کی عظمت بدلائل قاطعہ ثابت ہو چکی
ہو اور لوگوں نے اُسے اپنا امام تسلیم کر لیا ہو اب اگر یہ لوگ ایسے شخص کے کسی اقدام کی
: تدر اور اکتوبر :
Page 87
Al
حکمت کو نہ سمجھ سکیں تو اس کے یہ معنی نہیں ہوں گے کہ وہ اقدام حکمت سے خالی ہے بلکہ
اس پر یہ عام قاعدہ ہی چسپاں ہو گا کہ فصل الحكيم لا يخلوا عن الحكمة له
حکم و دانا کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا تاہم اس اصولی جواب کے بعد خاص
مستفسرہ امر کی یہ حکمت ظاہر ہے کہ رکوع محبوب و معبود کے سامنے آنے کی تعظیم میں
ہے اور پہلا سجدہ انتہائی قرب کے مقام میں پہنچ کر قدم بوسی کے قائمقام ہے اور
دوسرا سجدہ اس قرب کے مقام سے جدا ہوتے ہوئے واپسی کی کورنیش ہے جیسے
انسان محبوب بادشاہ کے دربار میں جانے پر بھی قدم بوسی کرتا ہے اور وہاں سے
رخصت کے وقت بھی قدم بوسی کہ کے واپس ہوتا ہے.پھر حالت سجدہ ایک انتہائی.قرب کا مقام ہے جیسا کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ اقرب ما يكون العبد من ربه
اذا كان ساجدا اور ظاہر ہے کہ جب انسان اپنے محبوب کے قرب میں ہوتا ہے
تو بار بار والہانہ انداز میں اس کے آستانہ پر جبیں سائی کرتا ہے.واللہ اعلم بالصواب
سوال : نمازہ کے سلام کے بعد دائیں یا بائیں طرف رخ کر نے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق
کیا تھا ؟
جواب: - حدیث میں آتا ہے کہ کان رسول اللہ صلی الله عليه وسلم یو منا فينصرف
على جانبيه جميعا على يمينه وعلى شماله (ترمذی ( یعنی آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد اپنا رخ انور لوگوں کی طرف کمر کے بیٹھتے تھے دائیں یا بائیں
جس طرف چاہتے رخ پھیر تھے اس کی کوئی خاص پابندی نہ تھی.تاہم بالعموم آپ
دائیں طرف سے ہی مڑتے تھے جیسا کہ مسلم کی روایت ہے :-
اكثر ما رأيت رسول اللہ صلی الله عليه وسلم ينصرف على يمينه.دنيل الأوطار هي
)
علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ حسب ضرورت جدھر سے چاہے منہ پھیر سکتا ہے.لیکن اگر کوئی خاص
ضرورت نہ ہو تو پھر دائیں طرف سے مڑنا بہر حال بہتر ہے.لعموم الأحاديث المصرحة بفضل التيامين.ضروری وضاحت
د الضامت)
١٠
۴
جیسا کہ اوپر اشارہ گذر چکا ہے نماز میں دل، زبان اور قسیم تینوں کا حصہ رکھا گیا ہے.دل میں
Page 88
۸۲
توجہ خشوع اور اللہ تعالیٰ کی محبت ہو.یہ نماز کا باطنی حصہ ہے.زبان سے حمد و ثناء اور ذکر و
تلاوت ہو اور جسم سے ادب و تعظیم یعنی خضوع کا اظہار ہو یہ نماز کا ظاہری حصہ ہے.پس
ظاہری لحاظ سے نماز کے دو حصے ہیں.حمد وثناء پر مشتمل کلمات ذکر جو زبان سے ادا ہوتے
ہیں اور دوسرے ادب و تعظیم معجز و انکسار پر مشتمل حرکات و سکنات جن کا اظہار اعضائے
جسم کے ذریعہ ہوتا ہے.کلمات ذکر کا مختصر بیان اوپر نماز پڑھنے کا طریق " میں آچکا ہے.کچھ مزید تفصیل بغرض افاده درج ذیل ہے :
(1) توجیه
- ;
نماز کی نیت سے جب کوئی مسلمان قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو تو سب سے پہلے تو جیہ یعنی
مندرجہ ذیل آیت پڑھے.اس کی پڑھنے سے تو اب زیادہ ملتا ہے.علاوہ ازیں تکبیر تحریمہ
کے بعد ثناء کی بجائے اس آیت کا پڑھنا بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت
ہے :-
اتي وجهت وجهي للذي میں پوری یکسوئی کے ساتھ اپنا رخ اس ذات کی
فَطَّر السموات والارض حنيفا طرف پھیر تا ہوں جنسی زمین اور آسمان
کو بنایا ہئے.وما انا من المشركين..میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں.(۲) دعائے استفتاح الصلوة
نماز پڑھنے کا طریق میں ثناء کا ذکر آیا ہے.اس کی بجائے مندرجہ ذیل دعا بھی پڑھ سکتے
ہیں.صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ کے بعد یہ دُعا پڑھا
کرتے تھے.اللهم باعد بینی و بین خطایای اے میرے خدا دوری ڈائد سے میرے اور ستر گنا ہو کے درمیان
كما باعدت بين المشرق والمغرب جیسے دوری ڈالدی تو نے مشرق اور مغر کے درمیان
اللهم نقني من خطاياي اسے خُدا صاف کہ مجھے میرے گنا ہوں سے
كما ينقى الثوب الابيض من الدنس جیسے صاف کر دیا جاتا ہے سفید کپڑا میل سے.-
Page 89
اللهم اغسلني بالماء و الثلج والبرد - اسے میرے خدا غسل دے مجھے پانی کے ساتھ اور برف
اور اولوں کے ساتھ.(۳) سورۃ فاتحہ کے ساتھ قرآن کریم کا کچھ زائد حصہ پڑھنا واجب ہے اور یہ حکم اس لئے ہے
تاکہ وقتاً فوقتاً انسان کو اللہ تعالیٰ کے مختلف حکموں کے علاوہ اُن کے حقائق و معارف کا
علم بھی ہوتا رہے جو قرآن کریم میں بیان ہوئے ہیں.بطور نمونہ دو سورتوں کا ذکر نماز پڑھنے
کا طریق “ میں ہو چکا ہے.قرآن کریم کے کچھ مزید متنے بھی لکھے جاتے ہیں تاکہ مزید قرآن کریم
یاد کرنے کا شوق پیدا ہو.آیة الکرسی :
اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلا هُوَ الْحَقُّ اللہ تعالٰی کے سوا کوئی اور قابل پرستش نہیں.وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا اور سب کا محافظ ہے.القيومة
لا تأخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمط نہ اس کو اُونگھ آتی ہے اور نہ نیند.لَهُ مَا فِي السَّماواتِ وَمَا فِي الأَرْضِ اُسی کا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے.من ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا کون ہے جو اسکی اجازہ کیے بغیر اس
کی حضور کسی کی سفارش
باِذْنِهِ يَعْلَمُ مَابین کر سکے.وہ جانتا ہے اس کو بھی جو ان لوگوں کے آگے
ايْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا پیش آنیوالا ہے اور اس کو بھی جوائن سے پیچھے گزر چکا
يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ ہے وہ اس
کے علم میں سے تھوڑے سے حصہ کا بھی
الا بما شاء وَسِعَ گریسته احاطہ نہیں کر سکتے مگر اتنے کا جتنا وہ چاہے.اس کا
السَّمَوتِ وَالْأَرْضِ ، وَلا اقتداره آسمان اور زمین پر حاوی ہے اور ان کی
يَعُودُهُ حِفْظُهُمَاجٍ وَهُوَ حفاظت سے تھکتا نہیں.اور بلند شان والا
الْعَلِيُّ الْعَظِيمُه له
اور بڑی عظمت والا ہے.ب.سورۃ بقرہ کی آخری آیت
لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا اللہ تعالٰی کسی پر اسکی طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہیں
وُسْعَهَاء لَهَا مَا كَسَبَتْ ڈالتا جو اپنے اچھا کام کیا اسکا فائدہ اس کو ملے گا اور
وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ جو برا کام عمداً کیا اس
کے یہ نتائج کا بھی وہی ذمہ دار ہو گا.رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا خدا سے ڈرنیوالے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے رب کریم بھول جائیں
: - البقره : ۲۵۶
Page 90
۸۴
إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأنَاج یا غلطی کر بیٹھیں تو ہمیں سزا نہ دیا.ربَّنَا وَ لَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا اسے ہمار سے رب
اور تو ہم پر ایسی کٹڑی ذمرا یہ ہیں
كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ نہ ڈالنا جیسی ان قوموں پر ڈالی تھیں جو ہم سے پہلے
مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا گزر چکے ہیں.اسے ہمارے رب اور اسی طرح ہم
مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ، وَاعْفُ سے وہ بوجھ نہ اٹھو ا جب سی اٹھانے کی ہم میں طاقت
عَنَّا وتمْ وَاغْفِرْ لَنَا وتف و نہیں.اور ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش اور ہم پر
ارْحَمْنَا وقف انت مؤلنا رحم کہہ تو ہمارا آتا ہے پس کافروں کے منجھوں
فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَفِرِينَ کے مقابلہ میں ہماری مدد کر.(ج ) سوره فیل
الَمْ تَرَ
كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ کیا تو نے نہیں دیکھا تیرے رب نے ہاتھی
بِأَصْحُبِ الْفِيلِ المْ والوں کا کیا حال کیا ؟ کیا اس نے اُن کے مکرو
يَجْعَلُ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيله فریب کو بے کا نہ نہیں کر دیا تھا.وَارْسُلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اور ان پر ٹھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیجے جو
ابا بيلَ تَرْمِهِمْ بِحِجَارَةٍ اُنہیں نشان والے کنکر مار تے تھے.منْ سَجِّيْلَ ، فَجَعَلَهُمْ پس اُنہیں کھائے ہوئے بھوسے کی
كَعَصْفِ مَا كُوله طرح کر دیا.( د ) سورة الفلق :-
ل اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلِق : توکہ کہ میں مخلوقات کے رب کی پناہ طلب کرتا
مِن شَرِّ مَا خَلَقَ : ہوں.اُس کی ہر مخلوق کے شر سے دیچنے کیلئے)
وَمِنْ شَرِ غَاسِقٍ اور ہر تاریک اور بے نور کے شر سے بچنے کیلئے )
إذَا وَقَبَ ، وَمِن جبکہ اس
کی تاریخی پھیل جائے اور تمام ایسے نفوس
ة
شَرِ التَّقْتَتِ فِي الْعُقَدِة کے شر سے بچنے کیلئے بھی، جو باہمی تعلقات کی گرمیوں
وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ میں تعلقات تڑوانے کی نیت سے پھونکیں
إِذَا حَسَدَة
مارتے ہیں.اور ہر حاسد کی شرارت سے بھی )
جب وہ حسد پر تل جاتا ہے.
Page 91
۸۵
(ھ) سورة الناس :
قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ تُو کہہ دے کہ میں تمام انسانوں کے رب
مَلِكِ النَّاسِ إِلهِ تمام انسانوں کے بادشاہ اور تمام انسانوں کے
:
النَّاسِ کا مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ معبود کی پناہ طلب کرتا ہوں.وسوسہ ڈالنے والے
الْخَنَّاسِ الَّذِی کے شر سے بچنے کیلئے جو وسوسہ ڈال کر خود پیچھے
:
،
يوسوس في صدور النَّاسِ کا ہٹ جاتا ہے.جو انسانوں کے دلوں میں شبہات
مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ : پیدا کر دیتا ہے.خواہ وہ منبع شر مخفی رہنے والی
ہستیوں میں سے ہو.خواہ عام انسانوں میں سے.(۴) تشہد اور درود شریف کے بعد جو مسنون دعائیں پڑھی جاتی ہیں اُن میں سے ایک دُعا کا ذکر نمازہ
پڑھنے کا طریق " میں گزر چکا ہے.چند مزید دعائیں یہ ہیں :-
(و) رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلوة اے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو نماز
و مِن ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَ تَقَبَّلُ کی پابندی کرنے والا بنا.اسے ہمارے رب
دُعَاء رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَ قبول کر میری دعا.اسے ہمارے رب پخش
لِوَالِدَى وَيَنمو منين دے مجھے اور میرے والدین کو اور تمام مومنوں
يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَاب ے کو محاسبہ کے دن.(ب) اللهُمَّ إِلَى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کھرا دینے والی
وَالْحُزْنِ وَاَعُوذُ بِكَ مِنَ معی سے اور فکر د رنج سے اور میں پناہ چاہتا
العجزِ وَ الكَيْلِ وَأَعُوذُ بِكَ ہوں فرض کی ادائیگی میں عاجز آجانے یا کاہلی یا شستی
من الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَاَعُوذُ بِكَ دکھانے سے.اور یکں تیری پناہ چاہتا ہوں بزدلی اور
مِنْ غَلَبَةِ اللَّيْنِ وَقَهرِ بُخل سے اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں قرض کے غلبہ
الرِّجَالِ، اللهم الفني بلايك اور لوگوں کی زبر دستی سے.اسے اللہ اپنے رزق حلال
عَنْ حَرَامِكَ وَأَغْنِي بِفَضْلِكَ سے میری ضرورت پوری کرتارہ میں بیچا رہوں اس رزق
عَنْ مَنْ سِوَاكَ.سے جسے تو نے حرام قرار دیا ہے اور اپنے فضل
دعائے قنوت) سے مجھے اپنے سوا دوسروں سے بے نیاز کر.( ج ) اللهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ اے مرے خدا مجھے ہدایت دیگران می شامل کر جن کو ہدایت دینے
Page 92
AY
وَعَافِنِي فِيْمَنُ مَا نَيْتَ تو نے فیصلہ کیا ہے.اور مجھے سلامت رکھکہ ان لوگوں میں
وَتَوَلَّنِي فِيْمَن تَوَلَّيْتُ شامل کر چین کو سلامت رکھنے کا تو نے فیصلہ کیا ہے اور
وَبَادِكَ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ مجھے دوست بنا کر ان لوگوں میں شامل کر جن کو دوست بنانے
وتنى شر ما قضیت کا تو نے فیصلہ کیا ہے.اور مجھے برکت عطا کر ان الفات
شَرَّ قَضَيْتَ
فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقضى میں جو تُو نے دیئے ہیں.اور مجھے بچائی چیز کی نقصان سے
عَلَيْكَ إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ جو تیری تقدیر میں نقصان دہ قرار دی گئیں کیونکہ توہی
والَيْتَ وَإِنَّهُ لايَعِد فیصلے کرتا ہے اور تیری مرضی کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں
منْ عَادَيْتَ تَبَارَكتَ کیا جا سکتا.سو وہ شخص ذلیل و خوار نہیں ہو سکتا جس کا
رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ وَصَلَّى الله تو دوست ہے اور نہ وہ عزت پاسکتا ہے جس کا
تو دشمن ہے.اسے ہمارے رب تو برکت والا اور
بلندشان والا ہے اور الہ تعالی ہمار سے نبی پر خاص
فضل فرمائے (جن کے ذریعہ ہمیں ایسی عمدہ دعاؤں
على النبي
کا علم حاصل ہوا ہے.(د)) اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ وَ اے میرے خدا ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں اور تجھے
نَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ سے بخشش مانگتے ہیں تجھ پر ایمان لاتے ہیں اور
وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْدَكَ وَنُشَى عَلَيْكَ تجھ پر توکل کرتے ہیں تیری بہترین تعریف کرتے ہیں
الْخَيْر وَنَشْكُرُ وَلا اور تیرے شکر گزار ہیں اور تیری ناشکری نہیں
تكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ کرتے اور ہم قطع تعلق کرتے ہیں اور چھوڑتے ہیں اس
من يَفْجُرُكَ اللهُمَّ کو جوتیرا نا فرمان ہے.اسے میرے خدا ہم تیری ہی
إيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصلي عبادت کرتے ہیں اور تیری فرمانبرداری کا دم بھرتے
وَنَسْجُدُ وَإِلَيْكَ نَسعَی وَ ہیں اور تیرے حضور سجدہ کرتے ہیں اور تیری طرف
نَحْفِدُ وَنَرْجُوا رَحْمَتَكَ دَوڑ کر آتے ہیں اور تیرے حضور کھڑے ہیں اور تیری
وَنَخْشَى عَذَابِكَ إِنَّ رحمت کے اُمیدوار ہیں اور تیرے عذاب سے
عَذَابَكَ بِالكَفَّارِ مُلْحِقُ ڈرتے ہیں.کیونکہ تیرا عذاب منکروں
کو پہنچنے والا
ہے وہ اس سے بچ نہیں سکتے :
Page 93
AL
ان
ج اور د- ذکر کو دعائے قنوت بھی کہتے ہیں.یعنی اظہار فرمانبرداری پر مشتمل عاجزانہ دکھا.یہ دعا آخری قعدہ میں پڑھی جاسکتی ہے.لیکن بالعموم وتم یا نماز فجر کی آخری رکعت میں رکوع کے بعد
بھی پڑھتے ہیں.اسی طرح مصائب اور بلیات کے دنوں میں بھی حسب موقع ان کا پڑھنا مسنون ہے
(۵) سلام کے بعد نماز ختم ہو جاتی ہے.نماز سے فارغ ہونے کے بعد تھوڑی دیر کے لئے دعا اور
ذکر میں مشغول رہنا موجب ثواب ہے اس موقع کی چند مسنون دعائیں درج ذیل ہیں :-
(3) استغفر الله - استغفر الله میں اللہ تعالیٰ سے بخشش چاہتا ہوں.میں اللہ تعالیٰ
استغفر الله - لا اله الا الله سے بخشش چاہتا ہوں.میں اللہ تعالیٰ سے بخشش
وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ لَهُ چاہتا ہوں.اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی قابل پرستش
الْمُلْكُ وَلَكَ الْحَمْدُ وَهُوَ نہیں.وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اُسکا
عَلَى كُلِّ شَئ قَدِير.ملک ہے اسی کیلئے حمد ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے.(ب) اللهُمَّ اَنتَ السَّلَامُ اے میرے خُدا تو سلامتی بھیجنے والا ہے اور تیری
وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكتَ طرف سے ہی امن و سلامتی ملتی ہے تو یہ کتوں کا مالک
يَا ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَام - ہے.اسے جلال اور عزت والے بادشاہ :
(ج) ذِكْرِك
( ج ) اللهُمَّ اعْنِي عَلى ذكرك اے میرے خُدا میری مدد کر کہ میں تجھے یاد کروں
وشكرك وحسن عبادتك تیرا شکر ادا کروں اور عمدگی کے ساتھ تیری عبادت
(ابوداؤد و نسائی) بجا لاؤں :
(د) اللهم اكفني بِحَلَا بِكَ اسے میرے خدا میری مدد کر کہ تیری طرف سے آیا ہوا
عَنْ حَرَامِكَ وَاغْنِي رزق حلال میرے لئے کافی ہوتا کہ حرام روزی سے
بفضلك عمن سواك.بچ جاؤں اور مجھے اپنے فضل سے اپنے سوا
اوروں سے مستغنی کر دے :
زه) ۳۳ بار سُبْحَانَ الله اللہ تعالی تمام نقائص سے پاک ہے.۳۳ بار الحمد لله تمام خوبیاں اللہ تعالٰی کے لئے ہیں.۳۴ بار الله اكبر
اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے.(و) اللهُمَّ اِنَّا نَجْعَلُكَ اسے میرے خُدا ہم ان بد خواہ دشمنوں کے سینوں میں تجھے
في نُحورِهِمْ رکھتے ہیں تیرا خوف ان کے دلوں میں بیٹھ جائے اور وہ
Page 94
AA
ونعوذ بِكَ مِنْ شُرُورِ هم سخت مرعوب ہو جائیں.اور ہم ان کی شرارتوں
رز يَا حَفِيظُ
يا عَزِيرٌ.سے تیری پناہ مانگتے ہیں.اسے حفاظت کرنے والے.اسے غالب آنے والے.اسے سچا ساتھ دینے والے
رَبِّ كُل شَيءٍ خَادِمُكَ اسے میرے رب سب چیزیں تیری خادم ہیں.رَبِّ فَاحْفَظْنِي اے میرے رب پس تو سہی میری حفاظت کر.وَالْمُرْنِي.وَارْحَمْنِي اور تو ہی میری مدد کر.اور مجھ پر رحم فرما :
(7) اللهم ارزشنِى حُبَّكَ اسے میرے خدا تو مجھے اپنی محبت عطا کر اور (ح) اللَّهُمَّ
رحُبِّ مَنْ أَحَبَّكَ ان لوگوں سے محبت کہ نیکی بھی توفیق عطا کہ جو تجھ سے
وحبَّ مَا يُقَدِ بنِي إِلَيْكَ مُحبت کرتے ہیں اور ان کاموں کے کر نیکی محبت
اللهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ بھی دے جو مجھے تیرے قریب کر دیں.اسے اللہ
احَبَّ إِلَيَّ مِنَ الْمَاءِ میرے لئے اپنی محبت کو ٹھنڈے پانی سے
بھی زیادہ محبوب بنا دے.البارد -
Page 95
(۲)
کلماتے ذکر کے علاوہ نماز سے متعلق کچھ افعال بھی ہیں جو نمازی کو بجالانے
پڑتے ہیں ان افعال کا اجمالی ذکر و پر طریق نماز میں آچکا ہے کچھ مزید تفصیل
درج ذیل ہے :-
(1) رفع یدین : تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانا آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم کی سنت سے ثابت ہے.ہاتھ اتنے اونچے اُٹھائے جائیں کہ انگوٹھے کانوں کی کو کے برابر
تک پہنچ جائیں.کانوں
کو ہاتھ لگانا ضروری نہیں ہتھیلیاں
نیم قبلہ رخ ہوں.انگلیاں نہ
بہت کشادہ اور کلی ہوئی ہوں.اور نہ بالکل بند اور یا ہم ملی ہوئی.بلکہ عام بھی حالت میں ہوں.اس پہلی بار کے علاوہ نماز کے دوران میں کسی اور موقع پر ہاتھ اٹھا نے ضروری نہیں ہیں.(۳) ہاتھ باندھنا :- تکبیر کے بعد ہاتھ سینہ کے نچلے حصہ پر باندھنا سنت ہے.دایاں ہاتھ
اوپر.بایاں نیچے ہو دائیں ہاتھ کی تین درمیانی انگلیاں بائیں کلائی پر ہوں اور انگوٹھے اور
چھنگلی سے پہنچے کے قریب سے کلائی کو پکڑسے ہوئے ہو.(۳) قیام : جو شخص کھڑا ہو سکے اس کے لئے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ضروری ہے.قیام نماز
کا ایک ضروری رکن اور فرض ہے البتہ اگر کوئی شخص بیماری یا معذوری کی وجہ سے کھڑا نہ ہو سکے
تو بیٹھ کر اور اگر بیٹھ نہ سکے تو لیٹ کر نماز پڑھ سکتا ہے.لیٹنے کا طریق یہ ہو کہ قبلہ کی طرف
پاؤں کر کے چت لیٹ جائے یا پھر دائیں پہلو پر لیٹے اور منہ قبلہ کی طرف ہو.(مم) رکوع : رکوع نماز کا ایک ضروری رکن اور فرض ہے.رکوع میں کمر اور سر برابر ایک
سیدھ میں ہوں.ہاتھ سیدھے اور گھٹنوں پر رکھے ہوں.انگلیوں سے ان کو پکڑسے ہوئے
ہو اگر بیماری یا عذر کی وجہ سے پوری طرح رکورخ نہ کر سکے تو سر کو حسب سہولت جھکانے سے
رکوع ادا ہو جائے گا.(۵) قومہ : - رکوع کے بعد کھڑے ہونے ، ہاتھ کھلے رکھنے اور کھڑے کھڑے رَبَّنَا وَلَكَ الْحَد
کہنے کو قومہ کہتے ہیں.یہ واجب ہے.(4) سجدہ :- زمین پر پیشانی رکھنے کو سجدہ کہتے ہیں.یہ نماز کا ضروری رکن اور فرض ہے.ہر رکعت میں دو سجدے ضروری ہیں.سجدہ کرنے والا اپنے دونوں گھٹنے دونوں ہاتھ.ناک اور
Page 96
9.پیشانی زمین پر رکھے.اسی طرح اس کے دونوں پاؤں بھی زمین سے لگے ہوئے ہوں ہاتھ اور
پاؤں کی انگلیاں قبلہ رخ ہوں.چہرہ دونوں ہاتھوں کے درمیان ہو.کہنیاں زمین سے کسی
قدیر اکٹھی ہوئی اور بازو پہلوؤں سے الگ ہوں پیٹر ان کے ساتھ لگا ہوا نہ ہو اگر بیماری
یا غذر کی وجہ سے اس طرح پر سجدہ نہ کر سکے تو جتنا ہو سکے اتنے سر کو جھکا دینے سے سجدہ
اور ہو جائے گا.سجدہ اللہ تعالیٰ کے حضور تذلل اور اظہار معجز و انکسار
کا انتہائی مقام ہے.یہ حالت
قرب الہی اور قبولیت دعا سے خاص مناسبت رکھتی ہے اس لئے سجدہ میں تسبیحات کے
علاوہ حسب مرضی و مناسبت وقت بکثرت دعائیں کرنا سنتِ رسول سے ثابت ہے.(6) جلسہ :- پہلے سجدہ کے بعد نگیر کہتے ہوئے اُٹھ کر بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں.یہ واجب ہے
بایاں پاؤں بچھا کر اُس پر بیٹھے اور دایاں پاؤں کھڑا رکھے اس کی انگلیاں قبلہ رخ ہوں دونوں
ہاتھ رانوں پر گھٹنوں کے قریب ہوں.ان کی انگلیاں بھی عام طبعی حالت میں نہ بہت کشادہ
نہ بہت بند ، سیدھی قبلہ رخ ہوں.اگر بوجہ بیماری را معذوری کوئی اس طرح نہ بیٹھ سکے تو
دونوں پاؤں بجھا کر یا کھڑے کر کے یا چوکڑی مار کر یا پاؤں آگے کر کے جیسے سہولت ہو بیٹھ سکتا
ہے.کچھ لمحے اس طرح بیٹھنے کے بعد دوسرا سجدہ کیا جائے.(۸) رکعت :- حسب وضاحت بالا قیام ، قرأت ، رکوع ، قومہ اور دونوں سجدوں کے مجموعہ کو
رکعت کہتے ہیں.کوئی نماز دو رکعتوں سے کم نہیں ہوتی.یسے اوپر
-
(۹) درمیانی قعدہ : اگر نماز تین یا چار رکعت کی ہو تو دور کعتیں پڑھنے کے بعد اس طرح بیٹھنا
جلسه بین السجدتین میں بیان ہوا ہے.درمیانی قعدہ کہلاتا ہے یہ واجب ہے
درمیانی قعدہ میں صرف تشہد پڑھتے ہیں.اس کے بعد نمازی تکبیر کہتے ہوئے تیسری رکعت
پڑھنے کے لئے کھڑا ہو جائے.(۱۰) اشارہ یا رفع سبابہ : تشہد پڑھتے ہوئے جب شہادت توحید کے مقام پر پہنچے تو
لا اللہ کہنے پر شہادت کی انگلی اٹھائے اور الا اللہ کہنے پر رکھ رہے یہ سنت ہے
اس کا ایک طریق جو سنت کے مطابق ہے یہ ہے کہ انگلی اُٹھاتے وقت انگوٹھے اور درمیانی
انگلی کا حلقہ بنائے اور چھنگلی اور اس کے ساتھ کی انگلی کو بھی موڑے جیسے گرہ بنائی جاتی ہے اور
اس کے ساتھ ہی شہادت کی انگلی مذکورہ الفاظ کے مطابق اٹھائے اور رکھے.یہ گویا للہ تعالے
Page 97
۹۱
کی وحدانیت کے متعلق زبانی شہادت کے ساتھ عملی شہادت بھی ہے.جب وہ کہتا ہے کوئی
ہمارا معبود نہیں تو اس نفی کی عملی تائید میں اپنی انگلی اٹھاتا ہے.اور پھر جب وہ کہتا ہے
مگر صرف اللہ ہی سچا معبود ہے تو اس اثبات کی عملی تائید میں اپنی انگلی نیچے رکھ دیتا ہے.جیسے انسان بات کرتے ہوئے عادتاً ساتھ ساتھ اپنے ہاتھ یا سر بھی ہلاتا جاتا ہے.(۱۱) آخری قعدہ :- نمازہ کی ساری رکھتیں پڑھنے کے بعد آخر میں مذکورہ بالا طریق جس کا ذکر جلسہ
بين السجدتین میں ہو چکا ہے کے مطابق بیٹھنا آخری قعدہ کہلاتا ہے.یہ نماز کا ضروری رکن
اور فرض ہے.اس قعدہ میں تشہد کے علاوہ درود شریف اور مسنون دعائیں بھی پڑھی جاتی
ہیں اس کے بعد سلام پھیرتے ہیں جس میں یہ نیت ہونی چاہیئے کہ جو انسان اور فرشتے میری
دائیں طرف ہیں ان کو سلام ہوا اور جو بائیں طرف ہیں ان کو بھی سلام ہوگو یا نمازی پہلے انت تعالی
کے دربار میں گیا ہو ا تھا اور اب وہاں سے باہر نکل کر اپنے ملنے والوں کے پاس آیا ہے اور
ان کو سلام کہتا ہے.(۳)
نماز پڑھنے کا طریق“ میں جو باتیں بیان ہوئی ہیں اُن میں بعض باتیں انتہائی اہم اور
رکن کی حیثیت رکھتی ہیں اور بعض کی اتنی اہمیت نہیں اس لحاظ سے تفصیلی تجزیہ مندجہ ذیل ہے.(۱) ارکان نماز
ا
الکان سکن کی جمع ہے.رکن نماز کے اہم اور ضروری حصہ کو کہتے ہیں.نماز کے ارکان سات ہیں
تکبیر تحریمہ قیام - قرأت - رکوع - دو سجدے.آخری قعدہ اور سلام.ان میں ہر ایک کا کرنا فرض
اور ضروری ہے.اگر جان بوجھ کر چھوڑے تو نمانہ دوبارہ پڑھے اور اگر بھول کر یا غلطی سے رہ جائے تو
اسے آخری قعدہ سے پہلے ادا کیا جائے اور پھر آخری تشہد میں مسنون دعاؤں کے بعد سجدہ سہو کیا
جائے.مثلاً کوئی بھول گیا اور دو سجدوں کی بجائے ایک ہی سجدہ کیا اور بعد میں یاد آیا تو پہلے یہ سجدہ کیا
جائے اس کے بعد سلام پھیرا جائے اگر تشہد وغیرہ پڑھنے بلکہ سلام پھیرنے کے بعد یاد آئے تو بھی
لے تب سندی :
Page 98
۹۴
ایسا ہی کرسے لینی پہلے اس بھولے ہوئے رکن کو ادا کر ہے.پھر آخری قعدہ کا تشہد درود شریف
وغیرہ پڑھے پھر سجدہ سہو کر سے اور اس کے بعد سلام پھیر سے لیے
(۲) واجبات نماز
واجب نماز کے ضروری حصے کو کہتے ہیں لیکن رکن سے اس کی اہمیت کسی قدر کم ہے.نماز
کے واجبات بارہ ہیں.(۱) سورہ فاتحہ پڑھنا (۲) ضم سورۃ یعنی فرضوں کی پہلی دو رکعتوں میں
اور سن و نوافل کی ساری رکھتوں میں سورۃ فاتحہ کے ساتھ قرآن پاک کا کچھ اور حصہ پڑھنا خواہ
پوری سورۃ ہو یا اس کا کوئی حصہ (۳) آمین کہنا.(۴) رکوع کے بعد سیدھے کھڑے ہونا
یعنی قومہ - (۵) پہلے سجدہ کے بعد بیٹھنا یعنی جلسہ - (4) ڈور کعتیں پڑھنے کے بعد بیٹھنا.یعنی
درمیانی قعدہ - (6) قعدہ خواہ درمیانی ہو یا آخری اس میں تشہد پڑھنا.(۸) اسلام کے وقت
منہ دائیں اور بائیں پھیرنا.(۹) ہر ین کو شہر ٹھہر کر پورے وقار طمانیت اور آرام سے ادا کرنا.((و) رکن
جسے تعدیل ارکان کہتے ہیں.(1) ہر رکن کو اپنی پنی جگہ ترتیب سے ادا کرنا جو پہلے ہے اُسے
پہلے اور جو بعد میں اُسے بعد میں.اسے ترتیب ارکان کہتے ہیں.دار) نماز با جماعت کی صورت
میں مغرب اور عشاء کی پہلی دو رکعتوں میں اور فجر جمعہ.عیدین کی ساری رکھتوں میں امام کا سورۃ
فاتحہ اور دوسری قرأت
کو بلند آواز سے پڑھنا اور ظہر و عصر کی ساری رکعتوں میں قرائت آہستہ
آورانہ سے پڑھنا نیز (۱۲) امام کے لئے تکبیر تحریمہ بلند آواز سے کہنا.-
ان واجبات میں سے اگر کوئی واجب جان بوجھ کہ عمداً چھوڑ دے تو نمازہ نہیں ہوگی اگر بھول
سے بہہ جائے تو اس کے تدارک کے طور پر آخر میں سجدہ سہو کیا جائے.مثلاً در میانی قعدہ بھول
گیا یا غلطی سے رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہوئے بغیر سجدہ میں چلا گیا تو اس قسم کی بھول یا غلطی کا
تدارک صرف سجدہ سہو کرنے سے ہو جائے گا.گویا رکن اور واجب میں یہ فرق ہے کہ رکن اگر بھول
سے رہ جائے تو اُسے ادا کرنا ضروری ہوتا ہے.اور پھر اس کے ساتھ سجدہ سہو بھی کرنا پڑتا
ہے.لیکن اگر واجب رہ جائے تو پھر اس کے ادا کرنے کی ضرورت نہیں اس کی بجائے صرف
سجدہ سہو کر لینا کافی ہے.(۳) سنون نماز
سنن سنت کی جمع ہے.اسنت سے مراد نماز کا وہ حصہ ہے جیسی کرنے سے ثواب ملتا ہے.
Page 99
سرو
اور اگر پھول سے رہ جائے تو سجدہ سہو کرنا ضروری نہیں ہوتا.نماز کے یہ سن پندرہ ہیں وہ کبیر تحریمیہ
کے وقت ہاتھ کانوں تک اٹھانا.(۲) ہاتھ باندھنا.(۳) ثناء پڑھنا.(۴) سورۃ فاتحہ کی قرأت سے
پہلے اعوذ باللہ پڑھنا یعنی تموز - (۵) رکوع میں جاتے ہوئے تکبیر کہنا.(۶) رکوع میں تین یا
تین سے زیادہ بار تسبیحات کہنا.(4) رکوع سے اٹھتے ہوئے جج اللہ کہنا یعنی تسمیع ، (۸)
کھڑے ہو کر ربنا ولك الحمد كہنا یعنی تحمید - (۹) سجدہ میں جاتے ہوئے اور سجدہ سے
اُٹھتے ہوئے تکبیر کہنا.(۱۰) سجدہ میں تین یا تین سے زیادہ تسبیحات کہنا.(11) درمیانی قعدہ
کے بعد تیسری رکعت کے لئے اٹھتے ہوئے تکبیر کہنا.دو تشہد میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی
شہادت کے وقت انگلی سے اشارہ کرنا.(۱۳) آخری قعدہ میں تشہد کے بعد درود شریف اور
دوسری مسنون دعائیں پڑھنا.(۱۴) فرض کی پچھلی ایک یا دو ر کھتوں میں صرف سورۃ فاتحہ پڑھنا.(10) نماز با جماعت کی صورت میں امام کا تکبیرات انتقالات نیز تسمیع و تسلیم بلند آواز سے کہنا.یہ سب باتیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہیں.ان کے کرنے سے ثواب
زیادہ ملتا ہے اور اگر کوئی جان بوجھ کر ان میں سے کسی سنت کو چھوڑتے تو گنہگار ہوگا.لیکن اگر بھوں
چوک ہو جائے تو درگزر کے قابل سمجھا جائے گا اور سجدہ سہو بھی ضروری نہ ہوگا.گو یا نماز میں ان
سکن پر عمل کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی امتحان میں اعلی نمبر لے کر پاس ہو اور اس
کامیابی پر اُسے خاص انعام کا مستحق قرار دیا جائے.اس کے برعکس جو شخص ان میں سے کوئی
سنت بھول گیا تو گو وہ پاس سمجھا جائے گا لیکن دوسرے درجہ میں اس لئے وہ کسی خاص انعام کا
مستحق نہیں ہوگا.م مستحبات
مستحبات مستحب کی جمع ہے.یعنی وہ بات جو نماز کو حسین بنا دیتی ہے اس کے کرنے سے ثواب
زیادہ ملتا ہے لیکن نہ کرنے پر کوئی گناہ لازم نہیں آتا مستحبات نماز یہ ہیں.(۱) قیام کے وقت
نظر سجدہ کی جگہ پر اور رکوع کے وقت پاؤں پر اور قعدہ کے وقت سینہ پر مرکوز رکھنا اور ادھر ادھر
نہ دیکھنا.رکوع میں ہا تھو گھٹنوں پر سیدھے اور پہلو سے جدا رکھنا.رکوع کے بعد کھڑے ہونے
کے وقت ہاتھ کھلے چھوڑنا اور سجدہ میں جاتے وقت اس ترتیب سے مجھکنا کہ پہلے گھٹنے پھر ہاتھ
پھر ناک اور آخر میں پیشانی زمین پر لگیں اور سجدہ سے اٹھتے وقت اُس کے الٹ کر نا یعنی پہلے پیشانی
Page 100
۹۴
زمین سے اٹھانا.پھر علی الترتیب ناک ، ہاتھ اور گھٹنے ہاتھ یا کسی اور چیز کا سہارا لئے بغیر سید ھے
کھڑے ہو جانا.جلسہ اور قعدہ میں ہاتھ رانوں پر گھٹنوں کے قریب رکھنا اور انگلیوں کا قبلہ رخ
ہونا.عورتوں کا تکبیر تحریمہ کے وقت ہا تھ کانوں تک اُٹھانے کی بجائے کندھوں تک اٹھانا.سورۃ فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں بڑی اور دوسری میں نسبتاً چھوٹی سورت پڑھنا یہ نماز با جماعت
کی صورت میں امام کا جہری نمازوں (مغرب و عشاء اور فجر میں بسم اللہ آہستہ آواز سے پڑھنا
مقتدیوں کا آئین " کسی قدر بلند آوانت اور تحمید آہستہ آواز سے کہنا.یہ سب باتیں نمانہ کو سنوار کر پڑھنے سے متعلق ہیں.ان کی پابندی سے ثواب بڑھ جاتا ہے.اور نماز میں خاص حسن پیدا ہو جاتا ہے.تاہم ان میں سے کسی امر کے رہ جانے سے نہ تو نماز میں کوئی
خاص نقص واقع ہوتا ہے اور نہ ہی سجدہ سہو کرنا لازم آتا ہے.(۵) مکروہاتے نماز
مکروہات مکروہ کی جمع ہے.یعنی ایسی بات جس کا کرنا نماز میں مکروہ اور نا پسندیدہ ہے.جیسے
بچنا چاہیئے.مکروہات نماز درج ذیل ہیں :-
نماز پڑھتے وقت ہاتھ آستینوں کے اندر رکھنا کنکھیوںسے ادہر ادہر دیکھنا.آسمان کی طرف دیکھنا
آنکھیں بند رکھنا.جلدی میں نماز پڑھنا.بلا عذر دیوار یا کسی اور چیز کا سہارا لینا.ننگے سر نماز پڑھنا.سجدہ میں پاؤں کی انگلیاں
زمین پر نہ لگا نا لہ اوپر اٹھا رکھنا.بھوک لگی ہوئی ہو اور کھانا لگا دیا گیا ہو.ایسی حالت میں نماز شروع کرنا.بیت الخلاو جانے کی ضرورت کے احساس کے باوجود نماز پڑھتے رہنا
قبرستان میں نماز پڑھنا جبکہ سامنے قبر ہو.صرف ایک طرف دائیں یا بائیں سلام پھیرنا.نمازہ پڑھتے
وقت بہت چست اور تنگ لباس پہننا جسے رکوع اور سجدہ کرنے یا فقرہ میں بیٹھنے میں دقت ہو.قیام کے وقت ایک ٹانگ پر کھڑا ہونا اور دونوں پاؤں پر یکساں زور نہ ڈالنا ، با وجود گنجائش کے ایک
ہی کپڑا جسم پر لپیٹ کر نما نہ پڑھنا مسجد میں جوتی سمیت نمانہ پڑھنا.ایسی جگہ نمانہ پڑھتا جس کا ماحول
صاف ستھرا پاک وصاف یا پرسکون نہ ہو.اور نماز میں یکسوئی پیدا نہ ہو سکتی ہو.مثلاً بیکریوں کے
باڑہ میں یا اصطبل میں یا بانہار میں جہاں ہر ایک کی آمد و رفت ہے نماز پڑھنا.کھلی میگہ میں جہاں
قریب اور سامنے سے راستہ گزرتا ہو سترا کھڑا کئے بغیر نماز پڑھنا تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ
کانوں سے بھی اوپر اٹھانا یا ہا تھوں کی انگلیاں بہت زیادہ پھیلا دینا.سلام کے جواب میں سر طلا دینا.له : بخاری ها :
Page 101
۹۵
کھانے کے بعد کلی کئے بغیر نماز پڑھنا کوئی چیز مثلاً پانی منہ میں دبا کر نماز پڑھنا.پہلی رکعت میں
قرآن کریم کا جو حصہ پڑھا ہے دوسری رکعت میں جان بوجھ کہ بلا کسی عذر کے اسی پہلا حصہ پڑھنا.نماز با جماعت کی صورت میں امام سے پہلے رکوع یا سجدے سے سر اٹھانا.ان میں سے کوئی بھی
بات نماز میں کرنا نا پسندیدہ ہے.اس سے نماز کا حسن داغدار ہوتا اور ثواب میں کمی آجاتی ہے.نماز پڑھنے والے کے سامنے سے گزرنا منع ہے.گزرنے والا گنہگار ہوگا.آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے اسے شیطان کہا ہے.آگے سے گزرنے والے کو بشر طیکہ وہ بہت قریب.گزر سے روکنا چاہیے.لیکن اگر روکنے کے باوجود گزر جائے تو نماز پڑھنے والے کی نماز میں کوئی
خلل واقع نہیں ہو گا نہ وہ ٹوٹے گی اور نہ مکروہ ہوگی.اگر نماز پڑھنے والے کے آگے سے گزرنے کی
اشد ضرورت ہو تو آگے کی دوسری صف سے گزرسکتا ہے گویا نمازی اور اس کی سجدہ گاہ یا کھڑے
کئے ہوئے سترہ کے درمیان سے گذرنا بہر حال منع ہے.نماز پڑھتے ہوئے اگر کوئی موذی جانور سامنے آجائے جیسے سانپ ، بچھو ، کتا وغیرہ تو حالت
نماز میں اُسے مار دینے یا پرے ہٹا دینے کی اجازت ہے اس سے نماز میں کوئی نقص اور حرج
واقع نہیں ہوگا.(۶) مبطلات نماز
مبطلات، مبطل کی جمع ہے یعنی وہ بات جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے.نمازہ کو توڑنے والی
باتیں یہ ہیں :.نماز کی کسی شرط یا اس کے کسی رکن یا واجب کو بلا کسی عذر کے جان بوجھ کر چھوڑ دینا.نماز
پڑھتے وقت جان بوجھ کر کسی سے بات
کرنا اسلام کا جواب دینا.ادہر ادہر منہ پھیر کر دیکھنا یا کھل کھلا
کو مہنس پڑنا ی نماز کے منافی کوئی اور کام کرنا.نمازمیں وضو کا ٹوٹ جانا.سنتر کھل جانا جیسم یا کپڑے
کو کوئی نجاست لگ جانا.ان میں سے کوئی صورت ہو نما نہ ٹوٹ جائے گی.اس لئے نئے سیر سے
سے نماز پڑھنا ضروری ہوگا.بے اختیار وضو ٹوٹ جانے کی صورت میں ایسا ہو سکتا ہے کہ خاموشی
سے کسی سے بات کئے بغیر انسان جاکہ جلد جلد وضو کر سے اور پھر اُسی جگہ سے آکر نماز شروع
کر دے جہاں چھوڑ گیا تھا.
Page 102
۹۶
مشتبهات
ـات
سوال ہے.کیا اندھیرے میں نماز پڑھنا منع ہے؟
جواب :.کوئی منع نہیں.احادیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے میں نماز
پڑھتے تھے اور جب سجدے کو جاتے تھے تو آگے حضرت عائشہ لیٹی ہوتی تھیں حضرت
عائشہ بیان کرتی ہیں کہ جب حضور سجدہ کرتے تو میں اپنے پیروں کو اکٹھے کر لیا کرتی تھی جائے
نماز میں جواب دینا
سوال : اگر ایک شخص نماز پڑھ رہا ہو اور باہر سے اس کا افسر آجاو ہے اور دروازہ کو ہلا ہلنا
کر اور ٹھونک ٹھونک کر پکار سے اور دفتر یا دوائی خانہ کی چابی مانگے تو ایسے وقت میں
اسے کیا کرنا چاہیئے.اسی وجہ سے ایک شخص نوکری سے محروم ہو کر ہندوستان واپس چلا گیا.جواب :.ایسی صورت میں ضروری تھا کہ وہ دروازہ کھول کر چابی افسر کو دے دیتا کیونکہ اگر اس کے
التوا سے کسی آدمی کی جان چلی جاو سے تو یہ سخت معصیت ہوگی.احادیث میں آیا ہے کہ نماند
میں چل کر دروازہ کھول دیا جا و سے تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی.ایسے ہی اگر لڑکے
کو کسی خطرہ کا اندیشہ ہو یا کسی موذی با نور سے جو نظر پڑتا ہو ضرور پہنچتا ہو تو لڑکے کو بچانا اور
جانور کو مار دینا اس حال میں کہ نماز پڑھ رہا ہے گناہ نہیں ہے اور نمازہ فاسد نہیں ہوتی
بلکہ بعضوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ گھوڑا کھل گیا ہو تو اُسے باندھ دینا بھی مفر نماز نہیں
ہے کیونکہ وقت کے اندر نمازہ تو پھر بھی پڑھ سکتا ہے.یاد رکھنا چاہیے کہ اشد ضرورتوں کے لئے نازک مواقع پر یہ حکم ہے.یہ نہیں کہ ہر ایک
قسم کی رفع حاجت کو مقدم رکھ کر نماز کی پروانہ کی جاو سے اور اسے بازیچہ اطفال بنا دیا
جائے.نماز میں اشغال کی سخت ممانعت ہے اور اللہ تعالیٰ ہر ایک دل اور نیت کو بخوبی
ہے.جانتا ہے کیے.سوال سے : مسجد میں جب نماز کھڑی ہو تو بعد میں آنے والا اونچی آواز سے سلام کہہ سکتا ہے ؟
جواب :.جماعت اگر کھڑی ہو تو باہر سے آنیوالے کیلئے اسلام علیکم کہنا من نہیں اس کی مرضی ہے
ه الفضل ۱۹ جنوری شر ہے.الحکم دسمبر منشارة
Page 103
9<
ہے سلام بلند آواز سے کہے یا آہستہ آواز سے حسب طبیعت عمل کر ہے.ہاں
نمازی جواب نہ دیں.سوال: - ایک نابینا شخص نماز با جماعت میں میرے ساتھ کھڑا تھا.چوتھی رکعت میں وہ التحیات
بیٹھنے کی بجائے کھڑا ہونے لگا.میں نے کپڑا کھینچ کر اُسے بٹھا دیا.کیا میرے اس فعل سے
نماز تو خراب نہیں ہوئی ؟
جواب : جو صورت آپ نے بیان کی ہے وہ جائز ہے اس کی نماز میں حرج واقع نہیں ہوتا
کیونکہ بوقت ضرورت معمولی حرکت ناقض نماز نہیں.مثلاً اگر کوئی باہر دروازہ کھٹکھٹا رہا ہو
تو سبحان اللہ کہ کہ اُسے مطلع کرنا کہ زمانہ میں ہوں یا اگر قریب ہے اور ضروری معلوم ہوتا
ہے تو چل کر کنڈ اکھوں دنیا یا اگر بچہ ہے تو اُسے شرارت کرنے سے معمولی طور پر روکنا یا
اگر رورہا ہے اور پاس ہے تو اُسے اُٹھا لینا یہ سب امور ضرورت پر منحصر نہیں.بشرط
ضرورت ان سے نمازہ نہیں ٹوٹتی.سوال : مسجد میں نمانہ ادا کرنے والوں کے سامنے سے بعض لوگ غلطی سے گزر جاتے ہیں.کئی نمازی
انہیں ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں.اس بارہ میں صحیح مسلکہ کیا ہے ؟
جواب : نماز پڑھنے والے کے آگے سے گزرنا گناہ ہے.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:.لو يعلم المار بين يدى المصلى ماذا عليه لكان ان يقف
اربعين خير الله من ان يمر بين يديا - (بخاری)
که اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والا جانتا کہ اُسے اس کا کتنا بڑا گناہ ہوتا ہے تو
چالیس تک کھڑے رہنا اس کے آگے سے گزرنے سے زیادہ بہتر سمجھنا یعنی ایک
انسان معمولی سی جلد بازی کے نتیجہ میں بعض اوقات اپنا بہت بڑا نقصان کر لیتا
ہے حالانکہ اگر وہ تھوڑا سا صبر کر لیتا تو وہ اس بڑے گناہ سے بچے بہاتا.ایک اور حدیث میں ہے کہ اگر کوئی شخص نمازی کے آگے سے گزرنے لگے تو نمازی کو چاہیے
کہ وہ اُسے رو کے اور اگر وہ نہ رکے تو اُسے دھکا دے کر پیچھے ہٹا دے کیونکہ وہ شیطان ہے
یعنی جلد بازی اور نماز کے عدم احترام کی وجہ سے وہ شیطنت کا مرتکب ہو رہا ہے دبخاری ومسلم )
باقی کسی کے گزرنے سے نماز پڑھنے والے کی نماز پر کچھ اثر نہیں پڑتا اس کی نمازہ صحیح ہے.صرف گزرنے والا ہی گہنگار ہوتا ہے.اب رہا یہ سوال
کہ اگر کوئی شخص نمازی کے آگے سے گزرنا چاہے تو
Page 104
۹۸
کتنی دور سے گزر ہے.اس کا جواب یہ ہے کہ ایک صف کا فاصلہ چھوڑ کر آگے سے انسان گزر سکتا
ہے.یوں
سمجھئے کہ سجدہ میں پیشانی کے رکھنے کی جگہ سے ایک دوفٹ ادہر سے گزرہ نا جائزہ ہو گا.در اصل ممانعت اس بات کی ہے کہ انسان نمازی اور اس کی سجدہ گاہ کے درمیان میں سے گزرے
حسب ضرورت سجدہ گاہ سے باہر کی طرف سے گزرنا منع نہیں.حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص
نیزہ یا کسی اور چیز سے اپنی صف کا تعین کرے یعنی سترہ رکھ لے تو اس در سے گزرنے میں کوئی حرج نہیں.حدیث کے الفاظ یہ ہیں :-
اذا صلی احدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئًا فان لم يجد فلينصب
عصا فان لم يكن معه عصا فليخط حطا ولا يضره ماربين
يديه.(مسند احمد)
یعنی اگر کوئی کھلی جگہ نماز پڑھنے لگے تو اُسے چاہیے کہ نماز شروث کرنے سے پہلے
اپنے سامنے کوئی چیز رکھ لے جو سترہ اور روک کا کام دے.اگر اس کے پاس اور
کوئی چیز نہ ہو تو اپنی چھڑی ہی کھڑی کر دے اگر چھڑی بھی نہ ہو تو خط کھینچ دے جیئے
معنے یہ ہوں گے کہ اس نشان کے اندر سے گزرنا منع ہے.البتہ اس کے باہر سے
انسان گزر سکتا ہے اور اس سے نماز پر کچھ اثر نہیں پڑے گا.چونکہ آجکل مساجد میں صفیں بچھی ہوتی ہیں یا صفوں کے نشان بنے ہوئے ہوتے ہیں اسلئے
اب مساجد میں اپنے طور پر شترہ کے لئے مذکورہ بالا قسم کے نشان
قائم کرنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں.غرض مختلف احادیث کی بناء پر علماء نے وضاحت کی ہے کہ نماندی سے قریبا تین ہاتھ کی دوری
سے انسان گزر سکتا ہے.اس گنجائش کی ایک اور دلیل یہ بھی ہے کہ حدیث میں نمازی
کو تلقین کی گئی ہے کہ وہ آگے سے
گزرنے والے کو ہاتھ سے رو کے اور یہ تب ہی ممکن ہے جبکہ وہ نمازی کے اتنے قریب سے گزار
رہا ہو کہ نمازی کا ہا تھ اس تک پہنچ سکتا ہو.یہ حکم تو بالکل نہیں کہ نماز پڑھنے والا آگے بڑھ کر اور
تو کر اور
کچھ قدم چل کر گزرنے والے کو جارو گئے.پس روکنے یا گزرنے والے کے گنہگار ہونے کا سوال تھی
پیدا ہوتا ہے جبکہ نمازی کے قریب سے اُسی صف پر سے گزرے جس میں نمازی نماز پڑھ رہا ہے.سامنے کی دوسری صف پر حسب ضرورت گزرنا منع نہیں.سوال : نماز کی حالت میں اگر کتا سامنے سے گزر جائے تو کیا جو حصہ ادا کیا جارہا ہے وہ دوبارہ پڑھتا ہوگا ؟
میں اگر
دنيل الأوطار )
Page 105
۹۹
جوا ہے :.نمازی کے سامنے سے اگر گنا گزر جائے تو اسکی نماز ٹوٹتی نہیں.جس حدیث کی طرف
آپ کا ذہن گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کتے یا اس قسم کی موزی چیز کے گزر جانے سے
طبیعت میں جو ہیجان یا اضطراب کی کیفیت بعض اوقات پیدا ہو جاتی ہے اُس سے نماز
ٹوٹنے کا اندیشہ ہے.گویا یوں فرمایا کہ ایسی صورت میں نمازہ ٹوٹی کہ ٹوٹی.اس لئے ان چیزوں
کو نماز پڑھنے کی جگہ سے دور رکھو.سجدہ ہو
نماز میں اگر کوئی ایسی غلطی سرزد ہو جہ سے نماز میں شدید نقص پڑ جائے مثلاً ہو ا فرض کی
ترتیب بدل جائے یا کوئی واجب جیسے درمیانی قعدہ رہ جائے یا رکعتوں کی تعداد میں شک نیر
جائے تو اس غلطی کے تدارک کے لئے دو زائد مسجد سے کہ نے ضروری ہیں اس کو سجدہ سہو کہتے
ہیں یعنی بھول چوک کے تدارک کا سجدہ.یہ دراصل دو مسجد سے ہوتے ہیں جو نماز کے آخری قعدہ
میں تشہد - درود شریف اور دعاؤں کے بعد کئے جاتے ہیں.جب آخری دُعا ختم ہو جائے تو تکبیر
کہہ کر دو سجدے کئے جائیں اور ان میں تسبیحات سجدہ پڑھی جائیں اس کے بعد بیٹھ کر سلام
پھیرا جائے.سجدہ سہو کرنے سے دراصل اس اقرار کی طرف اشارہ ہوتا ہے
کہ بھول چوک اور
ہر قسم کے نقص سے صرف رب العزت کی ذات پاک ہے انسان کمزور ہے.اس کی اس غلطی سے
در گذر فرمایا جائے اور اس کے بدنتائج سے اُسے بچایا جائے.غرض سجدہ سہو واجب کے ترک یا رکن میں تاخیر کرنے سے ضروری ہو جاتا ہے.مثلاً اگر رکوع یا.سجدہ بھول کر چھوڑ دے.نمازہ کے دوران میں یا بعد اُسے یاد آجائے تو اس کو چاہیے کہ تشہد سے
پہلے اس رکن کو پورا کر سے پھر تشہد اور درود شریف وغیرہ پڑھے اس کے بعد اس تاخیر کے تدارک کے
طور پر سجدہ سہو کرے اسی طرح واجب کے رہ جانے سے بھی سجدہ سہو ضروری ہو جاتا ہے.مثلاً جن
رکعتوں میں اونچی آواز سے قرات پڑھنی تھی اُن میں اونچی آواز سے نہ پڑھی یا سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی
سورة ياسورۃ کا کوئی حصہ نہ پڑھا یا درمیانی قعدہ بھول گیا یا رکھتوں کی مقررہ تعداد سے زائد رکھتیں
پڑھ لیں تو ان سب صورتوں میں سجدہ سہو واجب ہوگا.اور سجدہ سہو کرنے سے اس کمی یا غلطی کا
تدارک ہو جائے گا.ایک شخص نے یہ خیال کر کے کہ نماز پوری ہو چکی ہے سلام پھیر دیا.لیکن ابھی مسجد میں ہی تھا کہ
Page 106
معلوم ہوا کہ رکوت یا رکعت کا کوئی حصہ رہ گیا ہے تو پہلے وہ اس حصہ کو پورا کر سے اس کے بعد تشہد
وغیرہ پڑھ کر سجدہ سہو کر ہے.اس طرح سے اس کی نماز مکمل ہو جائے گی.اسی طرح اگر رکعتوں کی تعداد میں شک پڑ جائے.مثلاً یہ پتہ نہ چلے کہ ایک رکعت پڑھی ہے یا
دو.تین پڑھی ہیں یا چار تو کمی کے پہلو کو اختیار کیا جائے اور اس کے مطابق مزید رکعتیں پڑھی جائیں
اس کے بعد نماز کے آخر میں سجدہ سہو کیا جائے.امام اگر ایسی غلطی کرے جس سے سجدہ سہو ضروری ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ مقتدیوں کے
لئے بھی سجدہ سہو کرنا ضروری ہوگا.لیکن اگر صرف مقتدی سے ایسی کوئی غلطی ہو تو امام کی اتباع
کی وجہ سے اس کی غلطی قابل مواخذہ نہیں ہوگی اور اس کے لئے سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا.
Page 107
1+1
نماز کی اقسام اور انکی رکھاتے
نماز کی چار قسمیں ہیں.(1) مرض (۲) واجب (۳) سنت اور (۲) نفل.(۱) فرض نماز
فجر کی دو رکعت ظہر کی چار رکعت اگر جمعہ کا دن ہے تو ظہر کی بجائے جمعہ کی دو رکعت عصر
کی چار رکعت.مغرب کی تین اور عشاء کی چار رکعت.یہ پانچ نمازیں فرض ہیں.ان میں سے
اگر کوئی نماز غلطی یا بھول سے رہ جائے تو اس کی قضاء ضروری ہوگی اور اگر جان بوجھ کر کوئی چھوڑ
دے تو وہ سخت گہنگار ہوگا.عادہ تارک الصلواۃ مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں.(۲) واجب نمازه
و ترکی تین رکعت عید الفطر کی دو رکعت.عید الاضحیہ کی دو رکعت اور طواف بیت اللہ کی دو رکعت
یہ چاروں نمازیں واجب ہیں.اگر کوئی جان بوجھ کر چھوڑ دے تو وہ سخت گنہگار ہوگا اور اگر غلطی یا بھول سے
رہ جائیں تو ان کی قضاء فرض نہیں ہوگی.اس کے علاوہ اگر کسی وجہ سے نماز پڑھنے کی نذر مانی جائے تو
یہ نماز بھی واجب ہوگی کیونکہ نذر کا پورا کرنا ضروری ہوتا ہے.(۳) سنت نماز
فرض اور واجب نماز کے علاوہ ہو نماز آنحضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے بالعموم پڑھی ہے اور احادیث
میں اس کا ذکر موجود ہے.اس نماز کو سنت کہتے ہیں یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق اور آپؐ
کی روش پر چلتے ہوئے آپ کے ماننے والے یہ نماز بھی پڑھتے ہیں.یہ نماز پڑھنے کا بہت بڑا ثواب
ہے.اور تارک السنت قابل سرزنش ہے ، تاہم اگر یہ نماز کسی وجہ سے اس وقت کے اندر نہ پڑھی
جا سکے تو پھر اس کی قضاء نہیں ہے.
Page 108
١٠٣
فجر کی دو رکعت سنتیں فرض نماز سے پہلے پڑھی جاتی ہیں.یہ دور کھتیں آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم نے ہمیشہ پڑھیں اور ان کے پڑھنے کی تاکید فرمائی.اس لئے اگر کوئی شخص جماعت میں شامل ہو جائے
یا کسی اور وجہ سے فجر کے فرضوں سے پہلے یہ سنتیں نہ پڑھ سکے تو فرضوں کے معا بعد پڑھ لے یا پھر
سورج نکلنے کے بعد اور دوپہر ہونے سے پہلے پڑھے.ظہر کی فرض نماز سے پہلے چار رکعت اور فرض پڑھنے کے بعد دو رکعت نماز سنت
مغرب کے فرضوں کے بعد دو رکعت اور عشاء کی نماز کے بعد دو رکعت نماز سنت ہے.(۴) نفل نماز
ہے.تہجد کی آٹھ رکعت.عصر کی نماز سے پہلے چار رکعت ظہر کی دو سنتوں کے بعد دو رکعت.مغرب کی سنتوں کے بعد دو رکعت.مغرب کی اذان کے بعد اور فرضوں سے پہلے دو رکعت نفل
پڑھنے کی روایات بھی آئی ہیں.اس کے علاوہ حسب موقع و فرصت مغرب کی دو رکعت سنت اور دو نفل
کے بعد چھ رکعت مزید نفل پڑھنے کی روایت بھی آتی ہے.ان چھ رکعتوں کو سلاۃ الاوابین کہتے ہیں.اسی
طرح عشاء کی سنتوں کے بعد دو رکعت اور وتروں کے بعد دو رکعت نفل بیٹھ کر پڑھنے کی روایت بھی
آتی ہے.اشراق یعنی چاشت کے وقت کی دو رکعت ضحی یعنی دھوپ خوب چمک آنے کے وقت
اور دوپہر سے قبل دو تا آٹھ رکعت تحیۃ الوضو یعنی وضو کرنے کے بعد حسب موقع و فرصت دو نفل.تحیة المسجد یعنی مسجد میں داخل ہونے پر دو نفل نماز استخارہ یعنی طلب خیر کے دو نفل جو کسی کام کے
بابرکت ہونے کے لئے دعا کے طور پر پڑھے جاتے ہیں.حاجت روائی کی دعا کے دو نفل یعنی صلواۃ الحاجت
تحیر الشکر یعنی اچانک خوشی پہنچنے پر سجدہ شکر بھی کیا جاتا ہے.تو بہ کے دونفل - سفر سے واپسی کے
دو نفل.اس کے علاوہ سورج گرہن اور چاند گرہن کے وقت دو رکعت نمازہ مسنون ہے.اسی طرح
قحط سالی کے دور ہونے کے لئے دو نفل جسے صلوٰۃ الاستسقاء کہتے ہیں.صلواۃ التسبیح کی بھی ایک
روایت موجود ہے.اس کے علاوہ بھی جب موقع ملے اور دل کرے نفل نماز پڑھنا باعث ثواب ہے
سنت اور نفل نماز اصولا گھر میں ہی پڑھنی چاہیے.سنت اور نقل کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور اس
کے بعد قرآن پاک کا کچھ حصہ پڑھنا عینی ضم سورۃ ضروری ہے اور اگر بھوں سے رہ جائے تو سجدہ سہو
لازمی ہوگا.سنن اور نوافل فرائض کی تکمیل کرتے ہیں.بعض اوقات فرض کی ادائیگی میں کوئی غلطی یا کمی رہ حیاتی
بعض تو ان کی تشریح آئندہ صفحات میں آئے گی.
Page 109
ہے تو اس کی تلافی سنن اور نوافل کے ذریعہ ہو جاتی ہے.نوافل قرب الہی کا ذریعہ ہیں.فرضوں سے
ایمان قائم ہو جاتا ہے اور نوافل اس کے استحکام کا موجب بنتے ہیں.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا ہے کہ نوافل کے ذریعہ انسان اللہ تعالیٰ کا محبوب و مقرب بن جاتا ہے.تعدا د ر کھاتے کا اجمالی خاکہ
وقت نماز فرض واجب سنت نقل کل تعداد در استان
فجر کی سنتیں سے زیادہ کر رہیں
وتر
y+r
۱۲
A
۱۳
A
چار سنتیں فرضوں کیلے اور دو بعد
چار رکعت نفل فرضوں سے پہلے.رکعت صلواة الدامين
۲ رکعت نقل سنت کے بعد
اگر چه مستند مسلک یہی ہے کہ
و تر رات کی آخری نماز ہو تاہم و تمر
کے بعد دو رکعت نفل بیٹھ کر
پڑھنے کی روایت بھی آتی ہے.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
ہمیشہ پچھلی رات اُٹھ کر تہجد کی نماز پڑھی ہے.یہ نماز پڑھنے سے بے حد تو اب ملتا ہے.اس لئے
اس نماز کو سنت مؤکدہ کہنا چاہیے لیکن حرج سے بچانے کی خاطر چونکہ ہر فرد کے لئے اسکا پڑھنا
ضروری قرار نہیں دیا گیا اس لئے ہم نے اسے نفلوں میں شمار کیا ہے ورنہ در حقیقت یہ سنن
ندی میں شامل ہے.وتر عشاء کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن اگر تہجد کی نماز کے لئے اُٹھنا ہو اور اسکی
عادت ہو تو پھر وتر تہجد کی نماز کے بعد پڑھنے چاہئیں اس طرح تہجد کے وقت ۸ + ۳ = گیارہ رکعت
نماز ہوگی اور اگر وتر کے بعد دو نفل بھی پڑھے تو کل تیرہ رکھتیں ہوں گی.
Page 110
۱۰۴
سنون نوافل
سوال : سنن کے بارہ میں اصل ہدایت کیا ہے.نیز عصر اور عشاء سے قبل چار رکعت سنت
نماز پڑھتے کا کیا حکم ہے؟
جواب : نماز سے پہلے اور نمازہ کے بعد اصل سنتیں یعنی سنن مؤکدہ وہی ہیں جن کا ذکر کتب حدیث
و فقہ میں مشہور اور معروف ہے.یعنی فجر سے پہلے دو رکعت جن کی سب سے زیادہ تاکید ہے
ظہر سے پہلے چار اور بعد میں دو.مغرب کے بعد دو اور عشاء کے بعد دو رکعت نیز تجد
کی آٹھ رکعت.اصل تاکید انہی کے پڑھنے کی ہے.باقی نوافل ہیں جو چاہے پڑھے اور چاہیے
نہ پڑھے.ان میں سے بعض کے متعلق احادیث میں بھی ذکر آتا ہے اور بعض کے بارہ میں کوئی
ذکرہ نہیں ملتا.تاہم نقل نمانہ کے معنی ہی یہی ہیں کہ جتنے کوئی چاہے ثواب کی خاطر پڑھے.حدیثوں میں نماز سے پہلے جن نوافل کا ذکر آتا ہے وہ یہ ہیں.عصر سے پہلے چار
رکعت.اس کی روایت نسبتا زیادہ مستند ہے اور اس کے الفاظ یہ ہیں :-
عن ابن عمر عن النبي صلى
الله عليه وسلم قال رحم الله
امراً صلى قبل العصر اربعا - (ترندی ابواب الصلوة )
یعنی اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے اور اُسے برکت دے جو عصر سے قبل
چار رکعت نفل نماز پڑھے.مغرب سے پہلے دو رکعت کا ذکر بھی حدیث میں آیا ہے.حدیث کے الفاظ یہ ہیں :-
عن عبد الله بن مغفل قال قال النبي صلى الله عليه وسلم
صلوا قبل صلوة المغرب ركعتين صلوا قبل صلوة المغرب
ركعتين قال في الثالثة لمن شاء كراهية ان يتخذها
الناس سنة
یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا.مغرب سے پہلے دو رکعتیں پڑھو دوبارہ
یہی فرمایا اور تیسری بار فرمایا.جو چاہے ادا کرے.یہ آپ نے اس خدشہ
: بخاری کتاب التجد باب الصلوة قبل المغرب منثا :
Page 111
1-0
کے پیش نظر فرمایا.کہ کہیں لوگ اسے سنتِ مؤکدہ نہ بنا لیں.عشاء سے قبل چار رکعت پڑھنے کی روایت نسبتاً کمزور ہے تاہم روایت
موجود ہے اور وہ یہ ہے :-
نقل فى الاختيار عن عائشة رضى الله عنها انه عليه الصلوة
والسلام كان يصلى قبل العشاء اربعا ثم يضطجع له
یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے چار رکعت پڑھتے اور پھر کچھ
دیر کے لئے لیٹ جایا کرتھے.اس کے بعد مسجد میں عشاء کی نماز پڑھانے
تشریف لے جاتے.نوافل کے سلسلہ میں اصل حکم یہ ہے کہ اوقات منوعہ کے سوا باقی اوقات میں انسان
جب چاہے نفل پڑھ سکتا ہے.اس میں کوئی روک نہیں.پس اگر مندرجہ بالا روایات نہ
بھی ہوں تب بھی یہ جائز ہے کہ کوئی شخص عصر یا عشاء سے پہلے دو یا چار رکعت نماز
ھے یعنی یہ نوافل نہ تو ضروری ہیں اور نہ ہی منع.ا
وال :.ظہر کی نماز سے قبل دو رکعت سنت ادا کرنی چاہئیے یا چار رکعت
جواب:- دونوں طرح جائز ہے.چاہے تو نماز ظہر کے فرضوں سے پہلے صرف دو رکعت
سنت ادا کر سے اور چاہے تو چار رکوت لیکن ترجیح چار رکعت والی روایت کو ہے
کیونکہ امت کی اکثریت نے عملاً چار رکعت سنت کی پابندی کی ہے.چنانچہ حضرت امام
ابو حنیفہ حضرت امام مالک اور ان کے متبعین کا یہی مسلک ہے.حضرت مسیح موعود
علیہ السلام دیگر دینی مشاغل کے ہجوم کی وجہ سے اگر چہ بالعموم دورکعت ادا فرماتے تھے
لیکن آپ کے خلفاء اور جماعت احمدیہ کی اکثریت کا چار رکعت سنت پر ہی عمل ہے باقی
احادیث کے اس اختلاف کو یوں حل کیا گیا ہے.کہ اکثر تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے
پہلے چار رکعت ہی پڑھتے تھے لیکن کبھی کبھی دور کوت بھی پڑھ لیتے تھے.چنانچہ امام ابوجعفر
طبری لکھتے ہیں :.الاربع كانت في كثير من احواله والركعتان في قليلها - له
ایک تاویل یہ کی گئی ہے کہ حضور اگر یہ نماز گھر پڑھتے تو چار رکعت ادا فرماتے اور اگر
باہر مسجد میں پڑھتے تو دو رکعت.۵۴۵۳
١ بحر الرائق جلد به : : - نیل الاوطار ها : ص
Page 112
1.4
غرض جہاں تک جواز کا تعلق ہے دونوں صورتیں جائز ہیں.لیکن کثرت عمل کے لحاظ سے عوام کے
لئے چار پڑھنے کو ترجیح حاصل ہے.سوال : اگر فجرکی نماز رہ جائے تو یہ نماز قضاء کرتے وقت کیا سنتیں بھی پڑھنی چاہئیں یا نہیں.جواہے :.جب نماز فجر کی قضاء کرے تو ساتھ سنتیں بھی پڑھے.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور
آپ کے صحابہ کا یہی طریق عمل تھا آپ ان سنتوں کو ترک نہیں کرتے تھے.فجر کی سنتوں و فرضوں کے درمیان نوافل
ایک شخص کا سوال حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوا کہ عمار فجر کی
اذان کے بعد دوگانہ فرض سے پہلے اگر کوئی شخص نوافل ادا کر سے تو جائز ہے یا نہیں ؟
فرمایا : " نماز فجر کی اذان کے بعد سورج نکلنے تک دو رکعت سنت اور دو رکعت
فرض کے سوا اور کوئی نمازہ نہیں ہے " لے
جواب :-
سوال : چھوڑی ہوئی سنتیں جماعت کے بعد کس ترتیب سے ادا کی جائیں؟
- پہلے مقا بعد کی سنتیں پڑھے پھر اس کے بعد فوت شدہ سنتیں قضاء کر ہے.سوال : - مسجد میں ہوتے ہوئے جب تک اذان نہ ہو جائے سنت ادا کرنی چاہیے یا نہیں ؟ اگر
گھر میں پڑھ آئے تو کیا یہ جائز ہے ؟
جوا ہے :.اصل مسئلہ یہ ہے کہ وقت سے پہلے سنتیں ادانہ کی جائیں یہ ضروری نہیں کہ جب تک
اذان نہ ہو جائے مسجد میں سنتیں ادا نہ کی جائیں.جس مسجد میں نماز با جماعت ہوتی ہے
وہاں بھی اذان سے پہلے سنتیں ادا کی جا سکتی ہیں اس میں کوئی شرعی روک نہیں.کسی
حدیث میں ایسی ممانعت نظر سے نہیں گزری.گھر میں سنتیں ادا کر کے مسجد میں آنا زیادہ
بہتر اور موجب ثواب ہے.فرض نماز سے پہلے یا بعد نوافل
شریعیت میں نقل نماز سے مراد ایسی نماز ہے جو اپنی مرضی پر منحصر ہو.کوئی چاہے تو پڑھے
بدر به رفروری شار
Page 113
1.4
اور چاہے تو نہ پڑھے.کھڑے ہو کر پڑھے یا بیٹھ کر پڑھے.ویسے اصولاً کھڑے ہو کر نماز
پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے.اسلئے یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کس نفل نماز کو ترجیح حاصل
ہے اور کس کو نہیں.فرض نماز سے پہلے یا بعد سنن مؤکر کے بعد مندرجہ ذیل نوافل کا عوام میں رواج ہے.ظہر کی آخری دو سنتوں کے بعد دو رکعت بیٹھ کہ مغرب کی دو سنتوں کے بعد دو رکعت بیٹھ
کر اور چھ رکعت کھڑے ہو کر.وتروں کے بعد دو رکعت بیٹھ کر.سوال : کیا نوافل بیٹھ کر پڑھنے سے نصف ثواب ہوتا ہے.جبکہ نماز عشاء کے بعد نقل بیٹھ کر
پڑھنا سنت ہے.جوا ہے ؟.عام نفل میں یہ درست ہے کہ کھڑے ہو کر پڑھنے کی بجائے بیٹھ کر پڑھنے سے نصف
ثواب ملتا ہے.چنانچہ بخاری کی روایت ہے :-
عن عمران بن حصين انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن
صلواة الرجل قاعدًا قال ان صلى قائما فهو افضل ومن صلى
قاعدًا فله نصف اجر القائم ومن صلى نائمًا فله اجر القاعده
تاہم بعض احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم رات کو وتر کی نماز کے بعد
دو رکعت نفل بیٹھ کر پڑھتے تھے.چنانچہ ابن ماجہ کی روایت ہے :-
عن ام سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلى بعد الوتر
رکعتین خفيفتين وهو جالس
حضور کا یہ عمل غالباً جوانہ کے اظہار اور احساس سہولت کے پیش نظر تھا.-
سوال :.سنتوں کی ہر رکعت میں فاتحہ اور سورۃ کیا دونوں ضروری ہیں ؟
ہوا ہے :.سنتوں اور نوافل کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ اور قرآن کا کچھ اور حصہ پڑھنا دونوں ضروری
ہیں.چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارہ میں روایت ہے کہ :-
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرء في كل ركعة بفاتحة
الكتابة
یہ حدیث اس امر کو ثابت کرتی ہے کہ ہر رکعت میں خواہ وہ فرضوں کی ہو یا نفلوں کی آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ فاتحہ پڑھا کر تے تھے.اب رہا نوافل میں فاتحہ کے علاوہ قرآن کریم کا کوئی
ه - بخاری بحوالہ نیل الاوطار ہے : ہے :- مشکواۃ ص 4 : - بخاری ے
Page 114
FA
اور حصہ پڑھنے کا سوال تو ابن ماجد کی حدیث ہے :-
لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد وسورة له
یعنی صحت نماز کے لئے ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے علاوہ مزید کسی سورۃ کا پڑھنا بھی ضروری
ہے.اس کی مزید تشریح کشف الغمہ کی اس حدیث سے ہوتی ہے کہ :.كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرء مع الفاتحة في الأول الم
تنزيل السجدة وفى الثانية مع الفاتحة حمدفان وفي
الثالثة مع الفاتحة يسين وفى الرابعة مع الفاتحه تبارك
الذي بيده الملك ويقول صلى الله عليه وسلّم من صلى اريحا
بعد العشاء لا يفصل بينهن بتسليم شفع في اهل بينه كلهم
ممن وجبت له النار واجير من عذاب القبر له
یعنی آپ عشاء کی نماز کے بعد چار رکعت نفل ایک ہی سلام کے ساتھ پڑھتے.پہلی میں
سورۃ فاتحہ کے ساتھ سورۃ الم تنزیل السجدہ دوسری میں فاتحہ کے ساتھ محمد دخان - تیسری
میں فاتحہ کے ساتھ عیسین اور چوتھی میں فاتحہ کے ساتھ تبارک الذی پڑھتے اور فرماتے عشاء
کی نماز کے بعد چار رکعت نفل پڑھنا بڑے ہی ثواب کا موجب ہے.سوال: - سنتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد کچھ اور حصہ قرآن بھی ہر رکعت میں پڑھا جاتا ہے.مگر
فرائض میں صرف پہلی دو رکعتوں میں ایسا ہوتا ہے اس کے متعلق ہمیں کہاں سے علم ہوا ؟
جواب: - حدیث کی کتابوں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق وضاحت ہے کہ آپ فرض اور
سنتیں اسی طریق کے مطابق پڑھتے تھے.چنانچہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے :-
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقراء فى الأوليين من الظهر
والعصر بفاتحة الكتاب وسورتين وفي الآخرين بفاتحة
:
الكتاب -
یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کے فرضوں کی پہلی دو رکعتوں میں فاتحہ اور کوئی
دوسری سورۃ پڑھتے تھے اور پچھلی دو رکعتوں میں صرف سورۃ فاتحہ پڑھتے تھے.سنت اور فضل نماند کی ہر رکعت میں سورۂ فاتحہ اور قرآن کا کچھ حصہ پڑھنے کی ایک وجہ یہ
نیل الاوطار : : كشف الغمه ص۲۳ :
ه
Page 115
1.9
بھی ہے کہ اصل میں نوافل اور سنن میں ہر دور کعتیں مستقل یونٹ کی حیثیت رکھتی ہیں.اس
لئے جہاں چار چھ یا آٹھ رکعتیں نوافل کی نیت کی جائے وہاں دراصل دو دو رکعتوں
کی صورت میں الگ الگ نماز ہوگی.چنانچہ فقہاء نے اس کی تصریح بھی کی ہے.ہدایہ
میں ہے :-
القراة واجبة فى جميع ركعات النقل وفي جميع ركعات الوتر
اما النقل فلان كل شفع منه صلوة علحدة والقيام الى
الثالثة كتحريمة مبتدأة ولهذا لا يحب بالتحريمة الاولى
الارگفتانه
یعنی نفل اور سنتوں کی ہر رکعت میں قرأۃ واجب ہے.اسی طرح دتر کی رکعتوں کا
حال ہے کیونکہ نقل کی ہر دور کعتیں دراصل ایک مستقل اور علیحدہ یونٹ نہیں اور جب
ایک شخص دو رکعت پڑھ کر تیسری رکعت کے لئے اُٹھتا ہے تو اس کا اٹھنا نئے سرے
سے تکبیر تحریمہ کے مترادف ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی چار رکعت نقل کی نیت
کر کے اللہ اکبر کہے تو اس تحریمہ نیت سے صرف دو رکعت کا پڑھنا ہی ضروری ہوتا ہے
اور وہ دورکوت پڑھ کر سلام پھیر سکتا ہے.چار پوری کرنا اس کے لئے ضروری نہیں.سے
راسی طرح و تروں کے بارہ میں تصریح ہے کہ حضور علیہ السلام وتر کی ہر رکعت میں فاتحہ
اور سورۃ پڑھا کرتے تھے خواہ اکٹھی تین رکعت پڑھی جائیں.چاہے دو اور ایک کر کے.چنانچہ روایت ہے :-
كان النبي صلى الله عليه وسلم يقراء في الوترسبح اسم ربك
الاعلى وقل يايها الكافرون وقل هو الله احد - ته
برنبات الاعلمی پڑھتے تھے
یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم وستم کی پہلی رکعت میں مسبح اسم
دوسری میں قل یا یها الکافرون اور تیسری میں قُل هو الله احد.ه : هدايه مكنا : کے نسائی کتاب اللیل باب القراءة في الوتر م٣٣
Page 116
11.دعا اور سجدہ
سوال : کیا سجدہ میں اپنی حاجات کے متعلق دعائیں مانگنی جائزہ ہیں :.جواب :.نماز خصوصا سجدہ میں مختلف دعائیں مانگنے اور اپنی حاجات اللہ تعالیٰ کے حضور پیش
کہنے کی اجازت ہے.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے طریق عمل سے یہ امر
ثابت ہے اور حضور کا فرمان بھی ہے جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا : -
اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء له
یعنی سجدہ کی حالت میں انسان اللہ تعالیٰ سے قریب تر ہوتا ہے.اس لئے اس حالت میں بڑی
کثرت کے ساتھ دعائیں کرنی چاہئیں.اسی طرح ایک اور حدیث ہے :-
اما السجدة فاجتهدوا في الدعاء فَقَمِن ان يستجاب لكم - ته
کہ سجدہ میں خوب دعائیں کیا کرو کیونکہ سجدہ کی حالت قبولیت دعا کے لئے زیادہ مناسب ہے
اور اس کے قبول ہونے کی زیادہ امید کی جاسکتی ہے.رکوع و سجود میں قرآنی دُعا
سوال :.رکوع اور سجود میں قرآنی آیت پڑھنا کیسا ہے ؟
جواب :.سجدہ اور رکوع فروشنی کا وقت ہے اور خدا کا کلام عظمت چاہتا ہے ماسوا اس کے
حدیثوں سے کہیں ثابت نہیں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی رکوع یا سجود میں کوئی
قرآنی دعا پڑھی ہو.سنہ
سوال: - سجدہ میں قرآنی دعاؤں
کا پڑھنا کیوں ناجائز ہے.حالانکہ سجدہ انتہائی تذلیل کا مقام ہے؟
جواب : میرا تو یہی عقیدہ رہا ہے کہ سجدہ میں قرآنی دعاؤں کا پڑھنا جائز ہے.لیکن بعد میں حضرت
مسیح موعود علیہ السلام کا ایک ایسا حوالہ ملا جس میں آپ نے سجدہ کی حالت میں قرآنی دعادی
614°
مسلم کتاب الصلوة باب ما يقال في الركوع والسجود با سه کشف الغمه منشاء : الحكم ۳۰ ر اپریل مشاد
فتاوی مسیح و عورت )
Page 117
کا پڑھنا نا جائز قرار دیا ہے.اسی طرح مسند احمد بن حنبل میں بھی اسی مضمون کی ایک حدیث
مل گئی ہے.لیکن اگر میرے عقیدے کے خلاف یہ امور نہ ملتے تب بھی یہ دلیل میں معقول
قرار نہ دیا کہ سجدہ جب انتہائی تذلل کا مقام ہے تو قرآنی دعاؤں کا سجدہ کی حالت میں
پڑھنا جائز ہونا چاہیے.امام مالک کا عقیدہ تھا کہ سمندر کی ہر چیز حلال ہے.ایک دفعہ ایک شخص ان کے
پاس آیا اور کہنے لگا سمندر میں سوئر بھی ہوتا ہے کیا اس کا کھانا بھی جائز ہے.آپ نے
فرمایا سمندر کی ہر چیز کھانی جائز ہے.مگر سوئر حرام ہے اس نے بار بار یہی سوال
کیا مگر
آپ نے فرمایا میں اس سوال کا یہی جواب دے سکتا ہوں کہ سمندر کی ہر چیز حلال
ہے مگر سوئر حرام ہے.یہی جواب میں دیتا ہوں کہ سجدہ بے شک تذلل کا مقام ہے مگر قرآن عزت کی چیز
ہے اس کی دعائیں سجدہ کی حالت میں نہیں پڑھنی چاہئیں.دُعا انسان کو نیچے کی طرف
سے جاتی ہے اور قرآن انسان
کو اوپر کی طرف لے جاتا ہے.اس لئے قرآنی دعاؤں کا
سجدہ کی حالت میں مانگنا نا جائز ہے.جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے ایک بات مل
گئی تو پھر اس کے خلاف طریق کار اختیار کرنا درست نہیں.گروہ ہماری عقل میں نہ ہی آئے.سوال: کیا یہ جائز ہے کہ سجدہ میں دُعا کرتے وقت کچھ قرآنی الفاظ اور کچھ اپنے الفاظ ہوں ؟
جواب : - سجدہ میں قرآنی دعائیں تو جائز نہیں ہیں لیکن اگر انسان کے اپنے الفاظ ہوں اور
ان میں قرآن کی کسی آیت کا ٹکڑا آجائے تو اس میں کوئی حرج نہیں.دُعا بين السجدتين
سوال: کیا دعا بین السجدتین ضروری ہے ؟
جوا ہے.اس دُعا کے پڑھنے سے ثواب زیادہ ملتا ہے کیونکہ صحیح احادیث میں اس کا ذکر
آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر سیدھا پڑھا کرتے تھے.سوال : کیا نماز میں اپنی زبان میں دُعا مانگنا جائز ہے ؟
Page 118
ہوا ہے :.سب زبانیں خدا تعالیٰ نے بنائی ہیں.چاہیے کہ انسان اپنی زبان میں جس کو اچھی طرح
سمجھ سکتا ہے.نماز کے اندر دعائیں مانگے کیونکہ اس کا اثر دل پر پڑتا ہے تا عاجزی اور
خشوع پیدا ہو.کلام اپنی کو عربی میں پڑھو اور اس کے معنے یاد رکھو اور دعا بے شک
اپنی زبان میں مانگو.جو لوگ نماز کو جلدی جلدی پڑھتے ہیں اور پیچھے نبی دعائیں کرتے ہیں
وہ حقیقت سے نا آشنا ہیں دُعا کا وقت نماز ہے.نماز میں بہت دعائیں مانگو یہ
نماز با جماعت اور بلند آواز سے دعا
سوال :- امام اگر اپنی زبان میں مثلاً اُردو میں بآواز بلند دعا مانگتا جاوے اور پیچھے آمین کہتے
جاویں تو کیا یہ جائز ہے.جبکہ حضور کی تعلیم ہے کہ اپنی زبان میں دعائیں نماز میں کر لیا کرو.جواب : - دعا کو بآواز بلند پڑھنے کی ضرورت کیا ہے ، خدا تعالٰی نے تو فرمایا ہے، تضرعاً و
خفیہ اور دون الجهر من القول.22
سوال : عرض کیا کہ قنوت تو پڑھ لیتے ہیں.جواب فرمایا.ہاں ادعیہ ماثورہ جو قرآن و حدیث میں آچکی ہیں وہ بے شک پڑھ لی جا دیں.باقی
دعائیں جو اپنے ذوق و حال کے مطابق ہیں وہ دل میں ہی پڑھنی چاہئیں.ہے
سوال : ایک جماعت کا امام نماز میں بلند آواز سے اُردو زبان میں دعائیں مانگتا ہے ؟
حضرت خلیفہ اسیح الثانی.........نے فرمایا : -
اس سلسلہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا جو فتویٰ ہے وہ میں پہلے بھی کئی دفعہ
بیان کر چکا ہوں.حال ہی میں الفضل میں بھی وہ شائع ہوا ہے.حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا
ہی ارشاد ہے کہ نماز میں صرف ادعیہ ماثورہ بلند آواز سے پڑھنی چاہئیں.ہاں اگر اپنی زبان میں
کوئی دعا کرنی ہو تو بجائے بلند آواز کے دل میں ہو کر لینی چاہیے.میرا عمل اس سلسلہ میں یہ
ہے کہ ادعیہ ماثورہ کے پڑھتے وقت میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الہامات کو بھی شامل
کر لیا کرتا ہوں کیونکہ جو حکمت قرآن مجید اور احادیث کی دعائیں پڑھنے میں ہے.وہی حکمت
حضرت مسیح موعود علیہ السّلام کے الہامات میں بھی موجود ہے.:
اصل بات یہ ہے کہ جہاں تک ذاتی ضرورت اور خواہش کا سوال ہے انسان اپنی زبان
$19.4.بدریکم اگست تنتشله و ۲ جولائی منشد : سه : بدر یکم اگست سنشاه :
Page 119
میں ہی زیادہ موثر طریق اور محمدگی کے ساتھ دعا کر سکتا ہے.جس زبان میں انسان سوچتا اور
غور کرتا ہے اس میں اسے پوری مہارت ہوتی ہے اس لئے وہ صحیح رنگ میں اسی
زبان میں اپنے دلی جذبات اور اندرونی کیفیات کا اظہار کر سکتا ہے.اگر وہ کسی ایسی زبان
میں دعا کرے گا جس پر اسے پورہ سے طور پر تصرف حاصل نہیں تو وہ اپنے جذبات کا پورے
طور پر اظہارہ نہیں کر سکے گا.پس جہاں تک انفرادی طور پر خدا تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا سوال
ہے اپنی زبان میں دعا مانگنا ایک ضروری چیز ہے.لیکن اس
کے یہ معنی نہیں کہ ایسی دعائیں
بلند آواز سے کی جائیں یا اگر کوئی شخص امام ہو تو وہ اُردو یا کسی اور زبان میں اونچی آواز
سے دعائیں مانگنے لگ جائے وہ اپنے دلی میں تو ایسی دعائیں مانگ سکتا ہے اور اسے
ضرور مانگنی چاہئیں.مگر بلند آواز سے بالخصوص ایسی حالت میں جب کوئی شخص امام ہو
صرف ایسی دعائیں ہی مانگنی چاہئیں جو ادعیہ ماثورہ میں شامل ہوں اور جن کا قرآن وحدیث
میں ذکر آتا ہو.اس میں ایک یہ بھی حکمت ہے کہ اگر اپنی زبان میں دعا کی جائے تو یہ ضروری
نہیں ہوتا کہ انسان صحیح طور پر شریعیت کے تقاضے کو پورا کر سکے.مثلاً دعا کرتے وقت بعض
دفعہ انسان خدا تعالیٰ کو اس کی صفات یاد دلاتا ہے.بعض دفعہ خُدا کے بندے کے
ساتھ جو تعلقات ہیں ان کا واسطہ دیتا ہے " نے
سوال:.ایک دوست روزانہ مغرب کی نماز میں رکوع کے بعد النزانا دکھا کر تے ہیں.کیا یہ طریق
درست ہے
جواب : - التزام اور تہد کے ساتھ روزانہ آخری رکعت کے رکوع کے بعد کھڑے کھڑے لمبی دعا
کرنا مناسب نہیں بلکہ کبھی کبھی ترک بھی کر دینا چاہیئے.تاکہ اسے رواج نہ بنا لیا جائے.یا
ناواقف اسے نماز کا حصہ ہی نہ سمجھ لیں.یہی طریق حضرت مسیح موعود علیہ اسلام کا تھا اور ان کے
خلفاء کا.یعنی آپ دعا کر بھی لیا کرتے تھے اور بعض اوقات اسے ترک بھی کر دیتے تھے بالعموم
اس طرح سے دعا کر نے کا زیادہ اہتمام ان دنوں میں کیا جاتا جن دنوں کوئی خاص جماعتی ہم یا
جماعتی پریشانی در پیش ہوتی.تاہم ان دنوں میں بھی بعض اوقات اسے ترک کر دیا جاتا تھا.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایسا ہی مروی ہے.له الفضل
۱۸ جون شام
Page 120
۱۱۴
نماز کے بعد دعا
آج کل لوگ جلدی جلدی نماز کو ختم کرتے ہیں اور پیچھے لمبی دعائیں مانگنے بیٹھتے ہیں یہ بدعت
ہے.جس نماز میں تفریح نہیں خدا تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں.خُدا تعالیٰ سے رقت کے ساتھ دعا نہیں
وہ نماز تو خود ہی ٹوٹی ہوئی ہے.نماز وہ ہے جس میں دعا کا مزا آجائے.خُدا کی حضوری میں ایسی توجہ
سے کھڑے ہو جاؤ کہ رقت طاری ہو جاوے جیسے کہ کوئی شخص کسی خوفناک مقدمہ میں گرفتا ر ہوتا ہے
اور اس کے واسطے قید یا پھانسی کا فتویٰ لگنے والا ہوتا ہے.اس کی حالت حاکم کے سامنے کیا ہوتی
ہے.ایسے ہی خوفزدہ دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا چاہیئے.جس نماز میں دل کہیں
ہے اور خیال کسی طرف ہے.اور منہ سے کچھ نکلتا ہے وہ ایک لعنت ہے جو آدمی کے منہ پر واپس
ماری جاتی ہے اور قبول نہیں ہوتی.خدا تعالیٰ فرماتا ہے.ویل للمصلين الذين هم عن
صلاتهم ساهون جس میں مزا آجاوے ایسی ہی نمازہ کے ذریعہ سے گناہ سے نفرت پیدا
ہوتی ہے اور یہی وہ نماز ہے جس کی تعریف میں کہا گیا ہے کہ نماز مومن کا معراج ہے.نماز مومن
کی ترقی کا ذریعہ ہے.ان الحسنات يذهبن السيئات - نیکیاں بدیوں کو دور کر دیتی ہیں.دیکھو
بخیل سے بھی انسان مانگتا رہتا ہے تو وہ بھی کسی نہ کسی وقت کچھ دے دیتا ہے اور رحم کھاتا ہے
خدا تعالیٰ تو خود حکم دیتا ہے کہ مجھ سے مانگو اور میں تمہیں دوں گا.ہے
سوال : کیا نماز اور اذان کے بعد ہاتھ اٹھا کہ دعا مانگنا ضروری ہے ؟
جواب : - آذان اور نماز کے بعد ذکر الہی اور دعا مانگنے کا حکم ہے لیکن اس کے لئے ہاتھ اٹھانا ضروری
نہیں بلکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اسے پسند نہیں فرماتے تھے اس لئے دوام اور التزام
نہیں چاہئیے.کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ان مواقع پر ہاتھ نہیں اٹھایا
کرتے تھے.کسی صحیح حدیث سے حضور کا یا آپ کے صحابہ کا ایسا کرنا ثابت نہیں.تاہم اگر
کوئی چاہیے تو ان مواقع پر ہاتھ اُٹھا کر دعا مانگ سکتا ہے یعنی کبھی کبھار ایسا کہ نا جائز ہے.اس کے برعکس ان موقعوں پر ہاتھ اٹھانے کو ضروری سمجھنا اور جو ہاتھ نہیں اٹھاتے اُن پر
اعتراض کرنا بے معنی ہے.کیونکہ عبادت اور دعائیں جس طریق کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام
نے بالالتزام اور ضروری سمجھ کر نہیں کیا اُسے ضروری سمجھنا اور بالالتزام کرنا بدعت ہے.بدر یکم مئی سنه
Page 121
110
وكل بدعة في النار
عید کے دوسرے خطبہ کے بعد ہاتھ اُٹھا کر دعا مانگنے کے بارے میں نماز عید کا باب
دیکھیں.سوال: ۳۳ بار الحمد لله ، سبحان اللہ اور ۳۴ بار اللہ اکبر فرض نماز کے معاً بعد
پڑھنی چاہیے یا سنتوں کے بعد ؟
ہوا ہے :.نماز کے بعد ماثور ذکر کے بارہ میں اختلاف ہے.حنفی کہتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ فرض نمانہ
کے بعد صرف اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت ياذا الجلاك
والاکرام پڑھے.پھر سنتیں ادا کرے پھر اس کے بعد تسبیح و تحمید وغیرہ مسنون اذکار کرے
باقی احمد (امام مالک ، شافعی - احمد کہتے ہیں کہ سنتوں سے پہلے یہ ذکر کر نا زیادہ بہتر ہے.حدیث میں پوری وضاحت سے تفصیل نہیں ملتی.بعض احادیث میں آتا ہے کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو حجر فرض نمازوں کے فورا بعد اُٹھ کھڑے ہوتے تھے.یہ بھی آیا
ہے کہ زیادہ تر اللهم انت السلام.الحدیث پڑھتے تھے.کچھ حدیثیں ایسی
بھی ہیں کہ حضور نے فرض کے بعد لیے ذکر کو پسند فرمایا.معلوم ایسا ہوتا ہے کہ حالات کے
مانحت یہ تبدیلی ہوتی تھی کبھی فرض نماز کے مقابلہ ذکر کر لیا جاتا اور کبھی سنتوں کی ادائیگی
کے اور لے
سوال :- نماز کے بعد ذکر بالجہر کے بارہ میں کیا ارشاد ہے ؟
جواب :.جب دو باتیں جائز ہوں اور ان میں سے ایک راج نظر آئے تو اس پر عمل پیرا ہونا
زیادہ پسندیدہ ہے.اس کی عام مثال یہ ہے کہ آمین بالجہر اور باکسر کے متعلق دونوں
قسم کی حدیثیں ملتی ہیں لیکن زیادہ راجح بالجہر کہنا ہے اور اسی یہ ہمارا عمل ہے.لیکن دوسرا
طریق بھی درست ہے.اس لئے ہم بالسر کہنے کو غلطی یا گناہ نہیں سمجھتے.اسی طرح نمازنہ کے
بعد ذكر بالسر کو ترجیح حاصل ہے.عمل متواتر سے یہی ثابت ہے اور حضرت مسیح موعود علیہ اسلام
جو حکم و عدل ہیں اسی پر عمل پیرا ر ہے ہیں اور جماعت کا مسلک اس کے مطابق ہے.تاہم ذکر
بالجہر کی بھی بعض احادیث میں اجازت ہے اس کو اختیار کرنے والے غلط کار قرار نہیں دیئے
جاسکتے.اس لئے بہتر طریق اختیار کرنے کے لئے تلقین میں تو حرج نہیں لیکن جھگڑنا یا سختی
سے کام لیتا درست نہیں.صرف محبت سے سمجھا دینا یا اپنے مسلک کے جو انہ یا راج ہونے
: - الفضل ار ضروری اشته، ۱۸ مارچ : نه: نیل الاوطار جلد ۲ ۳ تا به او جزا المالک شرح موطا امام مالک جلد ا اوجز
Page 122
114
کے دلائل پیش کرنا کافی ہے تاکہ یہ غلط فہمی نہ رہے.تسبیح پھیرنے کے متعلق
سوال: تسبیح کے متعلق کیا حکم ہے؟
جواب :.فرمایا.تسبیح کرنے والے کا اصل مقصود گنتی ہوتا ہے اور اس گفتی کو پوڈر کر نا چاہتا ہے.اب تم خود سمجھ سکتے ہو کہ یا وہ گنتی پوری کرے اور یا توجہ کر ہے.اور یہ صاف بات ہے کہ گنتی کو
پوراکرنے کی فکر کرنے والا بچی تو یہ کہ ہی نہیں سکتا ہے.انبیاء علیہم السلام اور کاملین لوگ جن
کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذوق ہوتا ہے اور جو اللہ تعالٰی کے عشق میں نناشدہ ہوتے ہیں.انہوں
نے گنتی نہیں کی اور نہ اس کی ضرورت سمجھی.اہل حق تو ہر وقت خدا کو یاد کرتے رہتے ہیں ان
کے لئے گنتی کا سوال اور خیال ہی بے ہودہ ہے.کیا کوئی اپنے محبوب کا نام گن کر لیا کرتا ہے
اگر سچی محبت اللہ تعالٰی سے ہوا اور پوری توجہ الی اللہ ہو تو میں نہیں سمجھ سکتا کہ پھر
گنتی کا خیال
پیدا ہی کیوں ہوگا وہ تو اسی ذکر کو اپنی روح کی غذا سمجھے گا اور جس قدر
کثرت سے سوال کریگا
زیادہ لطف اور ذوق محسوس کرے گا اور اس میں ترقی کر سے گا.لیکن اگر محض گنتی مقصود ہوگا
تو وہ اسے ایک بیگا نہ سمجھ کر پورا کرنا چاہے گا.اے
سوال : کیا حائضہ درود شریف اور مسنون دعائیں وغیرہ پڑھ سکتی ہے ؟
جواب :- ایام حیض میں ذکر الہی یعنی درود شریف اور مسنون دعائیں پڑھنا منع نہیں.فقہ حنفی کی مشہور کتاب
شرح الوقایہ میں لکھا ہے " ولا تقرأ العائض ک جنب ونفساء وسائر الادعية
والاذکار لا باس بها یه یعنی جنبی اور نفاس والی کی طرح حائضہ بھی قرآن شریف نہ
پڑھے لیکن دعائیں اور اذکار کر سکتی ہے.اس میں کوئی حرج نہیں.سید نا حضرت خلیفتہ اسیح الثانی رضی اللہ عنہ، تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں :-
نفاس اور حیض کی حالت میں ذکر الہی منع نہیں.لوگ غلطی سے یہ سمجھتے ہیں کہ ایسی رات
میں دل میں بھی ذکر الہی نہیں کیا جا سکتا حالانکہ اگر ذکر الہی منع ہو جائے تو روحانیت بالکل
کر جائے " سے
الحلم ارجون شاه ، فتاوی مسیح موعود ملا له : شرح الوقایہ جنس : که : تفسير سورة مريم آیت ۲۷ منشا :
Page 123
۱۱۷
جر چهارم
متفرقات
1- اذار ہے.اذان کے الفاظ - طریق اذان - اذان کے بعد کی دعا.حکمت اذان اور اقامت -
- نماز با جماعت -:- نماز با جماعت کی حکمت.بلند یا آہستہ آواز سے قرات پڑھنے کی حکمت.- نماز جمعہ -: نماز جمعہ کا طریق.خطبہ ثانیہ کے مسنون الفاظ.۴.عید کی نمانہ.- نمازوں کو جمع کرنا.سفر کی نمانہ..خوف کی نمانہ -.-
- فوت شدہ نماز -
و - وتر
۱.تہجد کی نمانہ.۱۱ - نماز تراویح -
۱۲ - نماز کسوف و خسوف.۱۳ - نماز استسقاء -
۱۴- نماز استخاره -
۱۵ - نماز اشراق یعنی چاشت کی نمانہ.١٧ - صلواة التسبيح -
14
-14
سجدہ تلاوت.-۱۸ نمازہ جنازہ : نماز جنازہ کی ادعیہ ماثورہ مع تفصیل تکبیرات اور قبرستان کے مسائل."
Page 124
اذان
نماز با جماعت کے لئے مسلمانوں کو جمع کرنے کی غرض سے جو کلمات، بلند آواز سے ادا کئے
جاتے ہیں انہیں اذان کہتے ہیں.اذان مدینہ منورہ میں سندھ میں شروع ہوئی.مسلمانوں کی تعداد میں جب روز بروز اضافہ
ہونے لگا اور ان کے لئے نماز کے اوقات کی پہچان اور جماعت کے لئے وقت پر حاضر ہونے کی
تعیین دشوار ہو گئی تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ نمانہ کے وقت کی کوئی نشانی مقرر کر لیں تاکہ
جماعت سے نہ رہ جائیں.اس پر بعض نے ناقوس کی طرف اشارہ کیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا وہ عیسائیوں کا ہے.بعض نے بگل کا مشورہ دیا تو فرمایا.وہ یہودیوں کا ہے.بعض نے
رف کا ذکر کیا تو فرمایا وہ رومیوں کا ہے.بعض نے آگ جلانے کے متعلق کہا تو فرمایا.آگ سے
مجوسی روشنی کرتے ہیں.بعض نے جھنڈا بلند کرنے کی طرف اشارہ کیا کہ جب لوگ اس کو دیکھیں گے تو
ایک دوسرے کو بتا دیں گے حضور صلی الہ علیہ وسلم کو یہ بات بھی نہ بھائی.جب کسی بات پر اتفاق نہ ہو سکا تو
حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی فکر میں دعا میں لگ گئے.حضرت عبداللہ بن زید اسی سوچ ددعا کی حالت میں
رات سوئے تو خواب میں انہوں نے ایک فرشتہ دیکھا جنسی انہیں اذان اور اقامت سکھلائی.آپ
نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی خواب سنائی.یہ خواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سکتے
مطابق تھی حضرت عمر نے بھی ایسا ہی خواب دیکھا تھا.اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی اشارہ
یقین کرتے ہوئے اذان اور اقامت دونوں کا حکم دیا اور فرمایا اذا حضرت الصلاة فليؤذن
لكم احد كميه
اذان کے الفاظ :.الله اكبر - الله اکبر اللہ سب سے بڑا ہے.اللہ سب سے بڑا ہے.الله اكبر - الله اكبر.اللہ سب سے بڑا ہے.اللہ سب سے بڑا ہے.أشْهَدُ أن لا إله إلا الله - میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں.لا إِلَّا
اشْهَدُ ان ADATA ALTATENT TEN اللہ ہمیں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں.لا إله إلَّا
ه : بخاری :
ادلة
Page 125
119
ހ
اَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ
اللَّهِ مَیں گوہی دیتا ہوں کہ وحی کا یہ بنیامین یو اے اللہ کے دی ہیں
أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدٌ رَسُولُ
اللهِ - مَیں گواہی دیتاہوں کہ وحی کا یہ نام ای والے علم اللہ کے ولی ہیں
حتى عَلَى الصَّلواة حَتَّى عَلَى الصَّلوة چلے آؤ نمانہ کی طرف.چلے آؤ نمازہ کی طرف.حتى على الفلاح - حَتَّى عَلَى الْفَلاح - چلے آؤ نجات اور کامیابی کی طرف چلے آؤ نجات اورکامیابی کی طر
الله اکبر.الله اکبر اللہ سب سے بڑا ہے.اللہ سب سے بڑا ہے.لا إله إلا الله.اللہ تعالٰے کے سوا اور کوئی معبود نہیں.صرف صبیح کی نمازہ کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد یہ کلمے زائد کہے جائیں گے :-
-
الصَّلوةُ خَيْرُ مِنَ النَّوْمِ نماز نیند سے بہتر ہے.الصَّلوةُ خَيْرٌ مِّنَ التَّوْمِ نماز نیند سے بہتر ہے.اذان دینے کا طریق :-
نمانہ با جماعت کے لئے اذان ضروری ہے.اذان دینے کا طریق یہ ہے کہ جب نماز کا وقت شروع
ہو جائے تو مؤذن یعنی اذان دینے والا قبلہ کی طرف منہ کر کے کسی اونچی یا نمایاں جگہ پر کھڑا ہو جائے اور شہادت
کی انگلی اپنے کانوں میں ڈال ہے.اور بلند آواز سے مذکورہ کلمات اذان کہے.حتی علی الصلوة پر دونوں
بارہ اپنا منہ دائیں طرف پھیرے اور حتی علی الفلاح پر بائیں جانب پھیرے صبح کی اذان میں حتی
على الفلاح کے بعد دوبارا الصَّلوةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ بھی ہے.اذان با وضو دینی چاہیے.سوزن ایسے شخص کو مقرر کیا جائے جو خوش الحان ہو اس کی آواز بلند
ہو اور دینی مسائل سے اچھی طرح واقف ہو.حدیث میں آیا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ معمولی لوگوں
کو مؤذن مقررہ کیا جائے گا.مسلمانوں کو اس اندار سے سبق حاصل کرنا چاہیئے.جو لوگ اذان سُن رہے ہوں وہ بھی موذن کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ کلمات اذان دھراتے
جائیں.البتہ جب مؤذن حَتَّى عَلَى الصَّلوة يا حَتَّى عَلَى الْفَلَاحِ کہے تو سننے والے صرف لا حَوْلَ وَلاَ
قُوَة إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ پڑھیں.اذان ختم ہونے پر مون اور سننے والے دونوں مندرجہ ذیل
دعا مانگیں.اذان کے بعد کی دعا :-
اللهُم رَبَّ هذهِ الدَّعْوَةِ اسے اس کامل دُعا اور قائم رہنے والی عبادت کے
التَّامَّةِ وَالصَّلوةِ الْقَائِمَةِ خُدا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیاب ذریعہ.اعلیٰ
Page 126
ات مُحَمَّدَ نِ الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ فضلت اور بلند درجہ عطا فرما اور تو نے جس مقام
والدرجة الربيعَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا محمود کا ان سے وعدہ کیا ہے اُس پہ آپ کو
محمُودَ انِ
الَّذِي وَهَدْتَهُ إِنَّكَ مبعوث فرما.یقینا تو اپنے وعدہ کے خلاف
لا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.اذان کی حکمت :-
ہر گز نہیں کرتا..LAUR
اذان اسلامی شعار میں داخل ہے اور خدا تعالٰی کی عبادت کی طرف بلانے کا بہترین ذریعہ ہے جیسا کہ
اُوپر ذکر آچکا ہے.ہر قوم نے لوگوں کو عبادت کی خاطر جمع کرنے کے لئے مختلف طریقے اختیار کئے
ہیں کسی نے نرسنگا اور ناقوس سے کام لیا کسی نے گھڑیاں اور گھنٹے استعمال کئے لیکن اگر انصاف کی
اور
نظر سے دیکھا جائے تو کوئی وضع بھی اذان سے مقابلہ نہیں کر سکتی.ہمارے پیارے رسوئی مقبول صلی اللہ
علیہ وسلم نے ریکی بندشوں سیپیوں اور سینگوں کی تلاش سے اُمت کو سبکدوش کر دیا.علاوہ ازیں اذان
کے لئے کلمات ایسے منتخب کئے گئے جو فی الحقیقت اسلام کا خلاصہ ہیں.گویا عبادت کی عبادت اور
بلا دے کا بلاوا.دنیا میں ہزاروں حکماء اور ریفار مر گزرے ہیں.قومی گڈریے پیدا ہوئے ہیں مگر
تیتر بہتر بھیڑوں کو اکٹھا کرنے اور ایک جہت میں لانے کے لئے کسی نے ایسا نہ الا اور ایسا پر حکمت طریق
نہیں نکالا کسی نے کبھی ایسی ترئی نہیں پھونکی جس کی دلکش آواز مکاروحانی جوش اور خُدا کے حضور
دوڑ آنے کا ولولہ ہر انسان کے ظاہر و باطن میں پیدا کر دے.یہی وجہ ہے کہ آج تک کوئی قوم بھی ایسی
نہیں گزری جس نے شہروں اور وادیوں میں.مناروں اور پہاڑوں پر اس شد ومد سے اپنے سچے
اصولوں کی اس طرح مبادی کی ہو جس طرح مسلمانوں نے یہ منادی کی.سے
سوال : صبح کی اذان میں اَلصَّلوةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ کے الفاظ کب شامل ہوئے ؟
جواب : - (1) موذن مکہ حضرت ابو محذورہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم -
درخواست کی کہ حضور مجھے اذان سکھائیں.چنانچہ آپ نے مجھے اذان سکھائی اور فرمایا کہ جب
صبح کی اذان دینے لگو تو حتی علی الفلاح کے بعد دو دفعہ الصَّلوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ
بھی کہا کہ ویه
(۲) حضرت بلال اذان کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اطلاع دینے جایا کر تے
تھے کہ لوگ آ گئے ہیں.حضور نماز کے لئے تشریف لے آئیں.ایک دن بلال حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کے گھر گئے تو انہیں بتایا گیا کہ آپ سورہے ہیں.بلال نے بلند آواز سے کہا الصلوة خَيْرُ
من النوم حضور کو یہ الفاظ پسند آئے اور صبح کی اذان میں انہیں شامل کر لیا گیا ہے
نسائی کتاب الاذان باب الاذان فی السفر جلد اصلك : سه : - ابو ؟
Page 127
ان روایات سے ظاہر ہے کہ یہ الفاظ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہی اذان میں
شامل ہو چکے تھے.ا: کیا نماند با جماعت کے لئے اذان ضروری ہے ؟
جو اسے : ہاں اذان ہونی چاہیئے لیکن اللہ وہ لوگ جنہوں سے جماعت میں شامل ہونا ہے وہیں موجود
ہوں تو اگر اذان نہ کہی جائے اور صرف اقامت پر اکتفاء کیا جائے تو کچھ حرج نہیں.لوگوں
نے اس کے متعلق مختلف خیالات کا اظہار کیا ہے.مگر میں ایک دفعہ حضرت صاحب کے ہمراہ
گورداسپور کو جا رہا تھا.راستہ میں نماز کا وقت آیا.عرض کیا گیا کہ اذان کہی جائے ؟
فرمایا.کہ احباب تو جمع ہیں کیا ضرورت ہے.اس لئے اگر ایسی صورت ہو تو نہ دی جائے
ور نه اذان دینا ضروری ہے.کیونکہ اسی کسی دوسرے کو بھی تحریک نمانہ ہوتی ہے یہ
اگھر اکیلے نماز پڑھنی ہو تو اذان ضروری نہیں.جس صورت میں پہلے اذان نہیں ہوئی اذان دینی چاہیئے خواہ بالکل آہستہ آہستہ آوازہ
سے ہی کیوں نہ ہو.تاہم اگر کسی جگہ شرارت یا فتنہ کا ڈر ہو تو پھر ترک میں بھی کوئی حرج نہیں.صرف اقامت کافی ہوگی.سوال :.جمعہ کے دن مسجد میں جو سب سے پہلے آئے کیا وہی اذان دینے کا مستحق ہے ؟
جواہے :.اصل یہ ہے کہ اذان کے لئے جس شخص کو مقرر کر دیا جائے وہی اذان بھی دے اور
اقامت بھی کہے جمعہ کے روز دوسری اذان بھی وہی دے.البتہ منتظم مجانہ کی اجازت سے کوئی
اور شخص بھی دوسری اذان یا اقامت کہ سکتا ہے.لیکن اگر مسجد میں موذن مقرر نہیں تو پھر امام جسے چاہیے اذان اور اقامت کے لئے
کہہ دے یا جو اذان دے سکتا ہے اور موقع پر موجود ہے وہ اذان دیدے.تاہم یہ کوئی
مسئلہ نہیں کہ مسجد میں جو پہلے آئے اذان کہنا اس کا حق ہو جاتا ہے.حدیث میں آتا ہے کہ زیاد بن حارثہ نامی ایک شخص نے حضور علیہ السلام کی اجازت
سے اذان دی اور اقامت کے وقت حضرت بلال اقامت کہنے لگے تو آپ نے فرمایا کہ
جنسی اذان دی ہے وہی اقامت کہیے لیے
دوسری روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ محض افضلیت کے لحاظ سے ہدایت
ہے ورنہ یہ جائز ہے کہ اذان کوئی کہے اور اقامت کوئی اور.مگر امام یا اذان کہنے والے کی
له الفضل ۱۹ جنوری ۱۹۲۳مه:
: مسند احمد جلد م ا ، نیل الاوطار جلد ۲ صداها
Page 128
اجازت اور رضامندی سے یہ تبدیلی ہونی چاہیے....سوال : - باجماعت نماز میں دائیں طرف سے اقامت کہنے میں کیا حکمت ہے ؟
جواب : - آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دائیں جانب میں برکت ہے بہتر ہے کہ ہر کام دائیں
طرف سے ہو.تاہم یہ کوئی ضروری حکم نہیں کہ اقامت کہنے والا ضرور دائیں طرف ہی کھڑا ہو.وہ
شخص بھی اقامت کہہ سکتا ہے جو بائیں جانب کھڑا ہو.اس میں کوئی شرعی ممانعت نہیں.سوال ہے.اگر مغرب کی اذان بادلوں کے باعث غروب آفتاب سے پہلے ہو جائے اور نماز بھی پڑھ
لی جائے بعد میں پتہ چلے کہ سورج ابھی غروب نہیں ہوا تھا تو کیا یہ نماز دھرانی ضروری ہے ؟
جواب : نماز اگر وقت سے پہلے ادا کر لی جائے مثلاً مطلع ابر آلود ہو اور یہ معلوم نہ ہو سکے کہ
سورج غروب ہو گیا ہے یا نہیں اور نماز پڑھنے کے بعد معلوم ہو کہ سورج ابھی غروب نہیں
ہوا تھا تو ایسی صورت میں نماز دوبارہ پڑھی جائے.ہاں اگر لوگ جاچکے ہوں اور انہیں ایسی
صورت کا علم نہیں ہو سکا تو وہ معذور ہیں اس لئے عدم علم کی بناء پر وہ اس افادہ کے
مخاطب نہیں ہوں گے.حضرت ابو موسیٰ اشعری نے ایک بار اس طرح قبل از وقت نماز پڑھا دی بعد میں انہیں
اس کا علم ہوا.چنانچہ انہوں نے یہ نما نہ دوبارہ پڑھی سیہ
وقت کے اندر نماز پڑھنا صحت نماز کے لئے ضروری شرط ہے اور جس طرح کسی اور
شرط کے ترک سے (مثلاً طہارت نہ ہو خواہ ہوا ہی ایسی صورت ہو) اعادہ ضروری ہوتا ہے
اسی طرح اگر وقت سے پہلے غلطی سے نماز ادا ہو تو اس کا اعادہ بھی ضروری ہوگا.سوال: کیا مسجد کے اندر اذان دینا منع ہے ؟
جواب : مسجد میں اذان دینے میں کوئی حرج نہیں اس کی ممانعت کسی صحیح حدیث میں نہیں ہے.البتہ
یہ جائز ہے کہ اذان کے لئے مسجد کے ساتھ کوئی الگ اُونچی جگہ مینارہ یا چبوترے کی شکل بنادی
جائے.مکہ مکرمہ میں اذان کی جگہ مسجد حرام کے اندر ہے.حدیث میں ہے:-
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے زمانے میں جمعہ
کے دن منبر کے پاس (جو یقینا مسجد کے اندر رکھا ہوا تھا، ایک ہی اذان دی جاتی تھی.بعد
میں حضرت عثمان کے زمانہ میں دوسری اذان کا رواج پڑا.جو مسجد کے دروازہ پر پڑے ہوئے
ایک بڑے پتھر یہ کھڑے ہو کر دی جاتی تھی جس کا نام زوراء تھائیے
کشف الغمر كتاب الصلوة مث١٢ جلد اوّل :
بخاری باب التاذين عند الاذان يوم الجمعه ص ۱۳ جلد اول
Page 129
۱۲۳
اذان کے وقتے کوٹھے بات کرنا اور کچھ پڑھنا
عصر کی اذان ہوئی اور نواب صاحب اور مشیر اعلیٰ خاموش ہو گئے.حضرت اقدس امام علیہ السلام
نے فرمایا کہ اذان میں باتیں کرنا منع نہیں ہیں.آپ اگر کچھ اور بات پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھ لیں.کیونکہ
بعض باتیں انسان کے دل میں ہوتی ہیں اور وہ کسی وجہ سے ان کو نہیں پوچھتا اور پھر رفتہ رفتہ وہ برا
نتیجہ پیدا کرتی ہیں جو شکوک پیدا ہوں ان کو فوراً باہر نکالنا چاہیئے.یہ تیری غذا کی طرح ہوتی ہیں اگر نہ
نکالی جائیں تو سود ہضمی ہو جاتی ہے.ار اپریل تنشلم کو ایک شخص اپنا مضمون اشتہار دربارہ طاعون سنار ہا تھا.اذان ہونے لگی
وہ چپ ہو گیا.حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا.پڑھتے جاؤ.لے
الحکم مئی تار
Page 130
۱۳
اقامت
یہ اطلاع کمر نے کے لئے کہ اب بالکل نماز کھڑی ہونے لگی ہے اور امام نما نہ پڑھانے کے لئے
مصلی پر قبلہ رخ کھڑا ہو گیا ہے.اقامت کہی جاتی ہے.اقامت کہنے والا صف میں کھڑا ہوا.پینے
ہاتھ سید سے چھوڑے ہو.یہ ہوں.اقامت تیز روی سے جلدی جلدی ہی کہی جائے.جو شخص اذان
دے اقامت کہنے کا حق بھی اُسی کو ہے.اُس کی اجازت سے یا امام الصلوۃ کے کہنے پر دوسرا شخص بھی
اقامت کہ سکتا ہے.اقامت کے الفاظ یہ ہیں :-
اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللہ سب سے بڑا ہے.اللہ سب سے بڑا ہے.اشْهَدُ انْ لَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ یکی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبود نہیں.اشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ مَیں گواہی دیتا ہوں کہ توحید کا یہ پیغام دانیوں سے حمد اللہ
حَتَّى على الحلوة کے رسول ہیں.چلے آؤ نماز کی طرف.حَتَّى عَلَى الْمَلاحِ چلے آؤ نجات اور کامیابی کی طرف.قَدْ قَامَتِ المسلوة کھڑی ہوگئی نماند.قَدْ قَامَتِ المسلوة کھڑی ہو گئی نمانہ -
الله اكبر الله اكبر اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے.اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے.لا اله الا الله
إلة
اللہ تعالٰی کے سوا اور کوئی معبود نہیں.
Page 131
۱۲۵
نماز با جماعت
نماز با جماعت واجب ہے بلاعذرو مجبوری مردوں کے لئے فرض نمازہ اکیلے پڑھنا جائز نہیں.اس طرح ان کی نمازہ صحیح نہ ہوگی مسجد میں نماز با جماعت کے لئے ہی بنائی جاتی ہیں.با جماعت نماز کیے تھے یہ ہیں کہ ایک شخص نماز پڑھانے کے لئے آگے کھڑا ہو اور دوسرے
اس کے پیچھے صف بنائیں اور جس طرح وہ نماز پڑھے اسی طرح پیچھے اس کی اقتداء کرنے والے
نماز پڑھیں آگے کھڑے ہو کر نماز پڑھانے والے کو امام اور جو پیچھے صف میں کھڑے ہو سکتے
ہیں ان کو مقتدی کہا جاتا ہے.جو نیت امام کی ہو رہی مقتن کی ہونی چاہیئے.البتہ بوقت ضرورت
فرض پڑھنے والے کے پیچھے نفل نماز کی نیت ہو سکتی ہے.اس کے سوا باقی نماز کے ہرئیں میں
ادام کی پیشی را تباع ضروری ہے.ایسا نہ ہو کہ اس کے رکوع کرنے سے پہلے معتمدا رکورد
کہ سے یا اس کے سجدہ میں جانے سے پہلے سجدہ میں چلا جائے بلکہ نامہ کی حرکت کی سردی کی
جائے.ابو استار و آن هم سایت سے ہو ان دانمان میں ہوں.امام جماعت مؤمنین مبائعین میں سے ایسے شخص کو بنا یا بھا گئے ہو تاکہ
ہر
ہو.عاقل بالغ ہو.علیم دین سے واقف اور نماز کے مسائل جانتا ہو.ایسے شخص کو انام نہ بنایا جائے
جس کی امامت کو عام لوگ پسند نہ کر تے ہوں نما نہ پڑھانے کا سب ست مقدم میں بیعہ دست یا ان
کے مقرر کردہ امیر کو ہے.پھر اس شخص کو جسے لوگوں نے امام مقرر کیا ہوا ہے اس کی اجازت سے
کوئی اور
شخص بھی نما نہ پڑھا سکتا ہے.جو شخص قرآن پڑھ سکتا ہے وہ ایسے شخص کے پیچھے نماز نہیں
پڑھ سکتا جو ان پڑھ ہے.اور اگر بالغوں میں سے کوئی شخص پڑھا ہوا نہ ہو لیکن ایک سمجھدار نابالغ لڑکا
قرآن جانتا ہو تو ایسا لہ کا ان پڑھ نابالغوں کا امام بن سکتا ہے.عورت مردوں کی امام نہیں بن سکتی.البتہ اگر نماز پڑھنے والی ساری کی ساری عورتیں ہوں تو وہ
اپنے میں سے ایک کو امام بنا سکتی ہیں.اس صورت میں جو غوریہ ہے، امام..بنہ وہ صف کے اندر کھڑی
ہو.عورتوں کی نمانہ با جماعت کے لئے اذان کی ضرورت نہیں.صرف اقامت کافی ہے.عورتیں اگر
کسی جگہ جمع ہوں تو چاہیے کہ وہ نما نہ باجماعت ادا کریں.است ثواب زیادہ ملے گا گو ان کے لئے ایسا
Page 132
۱۲۶
کرنا ضروری نہیں.نماز با جماعت یعنی اقامت صلوٰۃ کا اصل وجوب مردوں کے لئے ہے عورتیں انکی متابعت
میں نماز باجماعت ادا کریں.ہاں اگر کسی جگہ صرف عورتیں جمع ہوں تو جیسا کہ بیان ہو چکا ہے وہ نماز
باجماعت پڑھ سکتی ہیں.نماز با جماعت میں امام تکبیرات تسمیع اور سلیم بلند آواز سے کہے.اگر امام کی آواز پچھلی صفوں
تک نہ پہنچے تو مقتدیوں میں سے کوئی بلند آوانہ شخص امام کے ساتھ تکبیرات اور تحمید اور سلیم اونچی آواز
سے کہے باقی مقندی آہستہ کہیں.مغرب، عشاء اور فجر کی نمازوں میں امام پہلی دو رکعتوں میں قرات بلند آواز سے کرے.مغرب اور عشاء کی بقیہ رکعتوں میں صرف سورۃ فاتحہ پڑھے اور وہ بھی آہستہ آوانہ سے ان کے ساتھ
کوئی اور سورت پڑھنے کی ضرورت نہیں اسی طرح ظہر اور عصر کی نمازوں کی ساری رکھتوں میں قرآت
آہستہ ہوگی یعنی اس قدر آہستہ کہ ساتھ نما نہ پڑھنے والائن نہ سکے کہ امام کیا پڑھ رہا ہے.مقتدی
صرف سورۂ فاتحہ پڑھے.اس کے ساتھ قرآن کریم کا کوئی اور حصہ پڑھنا ضروری نہیں.بلکہ اگر امام جہراً
قرأت کر رہا ہے تو مقتدی کو چاہیے کہ وہ قرآت کو توجہ سے سنے اور خود کچھ نہ پڑھے ہاں اگر نما نہ سیتری
ہے یا مقتدی امام کی آواز نہیں ٹن رہا تو وہ اگر چاہے تو سورہ فاتحہ کے ساتھ قرآن کریم کا کوئی اور حصہ
بھی پڑھ سکتا ہے گو یہ ضروری نہیں ہے
اگر امام بھول جائے تو اُسے توجہ دلانے کے لئے مقتدی سبحان اللہ کہیں لیکن اگر کوئی
عورت پیچھے نماز پڑھ رہی ہو تو وہ سبحان اللہ کہنے کی جگہ تالی بجائے.اگر امام قرائت میں غلطی کر سے یا
بھول جائے تو مقتدی اُسے صحیح آیت بتا سکتا ہے.اگر امام نماز میں غلطی ہو جانے کی وجہ سے
سجدہ سہو کہ سے تو مقتدی بھی ساتھ سجدہ سہو کریں.امام کو چاہیے کہ وہ اتنی بھی نماز نہ پڑھائے کہ مقتدی اکتا جائیں.اُسے کمزور.بوڑھے بیمار اور
کام کاج اور ڈیوٹی پر جلد جانے والوں کا خیال رکھنا چاہیے.نمازیوں کی صفیں بالکل سیدھی ہوں.سف باندھنے والے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر
کھڑے ہوں.درمیان میں جگہ خالی نہ ہو پہلے پہلی صف کو پورا کیا جائے پھر دوسری صف بنائی جائے
یہی طریق آختہ تک قائم رہے.پہلے مردوں کی صفیں ہوں ان کے بعد بچوں کی اور پھر عورتوں کی یا پھر
عورتوں کی صفیں علیحدہ ایک طرف با پردہ جگہ میں ہوں لیکن امام اور مردوں کی صفوں سے عورتوں کی
: تفر کو
Page 133
صفیں اتنے زیادہ فاصلہ پر نہ ہوں کہ اُن کی صفوں کی جگہ بالکل الگ تھلگ ہی نظر آئے.مقصد یہ کہ
مرد ، عورت اور بچے تینوں نہ ایک ہی صف میں کھڑے ہوں اور نہ ہی عورتوں کی صف مردوں کی صف
سے آگے ہو.نماز با جماعت کے لئے کم از کم دو آدمی ہونے چاہئیں تاہم جتنے زیادہ لوگ جماعت میں شامل
ہوں اتنا زیادہ ثواب ملے گا.نماز پڑھنے والے اگر صرف دو ہوں تو مقتدی امام کے ساتھ دائیں
جانب کھڑا ہوا اور اگر نما ز پڑھنے اپنے دوسر زیادہ ہوں تو پھر امام آگے کھڑا ہو اور مقتدی پیچھے سف
بنائیں.پہلی صف میں امام کے قریب ایسے لوگ کھڑے ہونے چاہئیں جو ذی علم اور متقی ہوں.اگر نماز
کے دوران میں امام کو کوئی ایسا حادثہ پیش آجائے کہ وہ نماز پڑھانے کے قابل نہ رہے مثلاً اس کا
و نوٹوٹ جائے تو وہ خود معلی سے ہٹ جائے اور اس کے قریب ہی جو لوگ کھڑے ہیں اُن میں
سے کسی کو اپنی جگہ کھڑا کر دے تاکہ وہ لوگوں کو بقیہ نماز پڑھائے ایسا کرنے سے نماز کا تسلسل نہیں ٹوٹے گا.صفوں کے پیچھے یا صفوں سے علیحدہ اکیلے کھڑے ہونا درست نہیں اگر اگلی صف میں کوئی جگہ نہ ہو
تو اگلی صف میں سے کسی آدمی کو پیچھے کر کے اس کے ساتھ صف بنا کر کھڑا ہونا چاہیئے.اگر مجبوری ہو اور
دوسرے آدمی کو ساتھ کھڑا کر نا ممکن نہ ہو تو پھر اکیلے بھی کھڑا ہو سکتا ہے.اگر امام بوجہ بیماری یا ضعف کھڑا ہونے سے معذور ہوا اور وہ بیٹھ کر نماز پڑھائے تو مقتدی
جو مقدور نہیں ہیں کھڑے ہو کر اس کی اقتداء میں نمانہ ادا کریں.جو شخص ایسی حالت میں آکر شامل ہو کہ امام ایک رکعت یا زیادہ رکھتیں پڑھ چکا تھا تو جس حالت
میں بھی امام ہے اسی حالت میں بعد میں آنے والا سا تھ شامل ہو جائے.ایسے شخص کو مسبوق کہتے ہیں
یعنی امام اسی آگے نکل گیا ہے اور وہ پیچھے رہ گیا ہے.امام جب اپنی نماز ختم کرے تو مسبوق
سلام پھیر نے کی بجائے اللہ اکبر کہتے ہوئے اُٹھ کھڑا ہو اور اپنی بقیہ نماز کو اس طرح پڑھے کہ گویا وہ زمانہ
شروع سے اکیلے پڑھ رہا ہے.یعنی پہلی رکعت ثناء اور اعوز سے شروع کرے اور فاتحہ کے بعد کوئی
اور سورۃ بھی پڑھے.دوسری رکعت بھی اگر اس نے پڑھتی ہے تو اس میں فاتحہ کے علاوہ کوئی اور سورت
پڑھے.البتہ اگر اس کو امام کے ساتھ ایک ہی رکعت ملی ہے تو اس کے لیئے یہ اجازت ہے کہ وہ درمیانی
قعدہ کے لئے ایک رکعت پڑھنے کے بعد ہی بیٹھ جائے یا دو رکعت پڑھ کر قعدہ میں بیٹھے.دونوں
صورتوں میں سے کوئی ایک سورت اختیار کی جاسکتی ہے.جو شخص رکوع میں آکر شامل ہو یعنی امام کے سر
Page 134
۱۲۸
اٹھانے سے پہلے پہلے رکوع کے لئے جنگ جائے تو اس کی یہ پوری رکعت شمار ہوگی ورنہ اس کی
یہ رکعت فوت شدہ ہوں جیسے وہ بعد میں پوری کرے گا.ایک شخص امام کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا کہ اسکا وضو ٹوٹ گیا اور وہ خاموشی سے وضو کرنے چلا گیا اور پھر آ کر
شامل ہوگیا یاس پر نیند کا غلبہ ہوگیا.یاکوئی اور درپیش آگیا اوروہ امام کے ساتھد کو میں کم ہوسکایا امام مسجدیں
جا چکا تھابہ رکوع سے اٹھ اور اسطرح وہ کام کیساتھ تو نہیں کرسکا یا امام نے اسکی بج میں جان سے پہلے اپنا سجدہ کمل کر لی تو اس
قسم کی سب صورتوں میں ایسا شخص جلدی سے اس فوت شدہ مکن یعنی رکوع یا سجدہ کو پورا کرہ سے
اور اس کے بعد اپنی نمازہ کو امام کے ساتھ جاری رکھے.لیکن اگر وہ ایسے وقت میں شامل ہوا یا
اپنی غلطی سے متنبہ ہوا کہ امام اس کے بعد کی رکعت کے رکوع میں جا چکا تھا اور یہ فوت شدہ ارکان
کو پورا کر کے امام کے ساتھ رکون میں شامل نہیں ہو سکتا تھا تو وہ بجائے فوت شدہ رکن کو
گورا کرنے کے امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہو جائے اور جو رکعت اس کی رہ گئی ہے یا جس رکعت
میں استی یہ غلطی سرزد ہوئی ہے اس ساری رکعت کو امام کے قابہ رغ ہونے کے بعد پوری کرے یہ
اس کی وہ رکعت ہوگی جو اس کی رہ گئی ہے یا جس میں اس سے غلطی سرزد ہوئی ہے.مثلاً اگر یہ
دوسری رکعت تھی تو وہ اُسے دوبارہ پڑھتے وقت ثناء اور آخوذ نہیں پڑھے گا اور اگر تیسری
رکوت تھی تو اس میں فاتحہ کے بعد سورۃ نہیں پڑھے گا یہی حکم ملحق کا ہے.مقتدی امام کے پیسے سورۃ فاتحہ آہستہ آواز سے ضرور پڑھیں سوائے اس کے کہ مقتدی
امام کے ساتھ یہ کوع میں آکر شامل ہوا ہو اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے لئے وقت نہ ہو ایسی صورت
میں اس رکعت کی سورۃ فاتحہ معاف ہوگی.سورۂ فاتحہ کے علاوہ مقتدی کے لئے قرآن کا کوئی اور
حصہ پڑھنا ضروری نہیں.اُسے چاہیئے کہ وہ امام کی قرأت توجہ سے سنے اور اپنی توجہ اس طرف
مصروف رکھے.جو شخص گھر میں یا کسی اور جگہ نماز پڑھ کر مسجدیں آیا اور اس مسجد میں نماز ہو رہی تھی تو اس
شخص
کو جماعت میں شامل ہو جانا چاہیے اور یہ خیال نہیں کرنا چاہیئے کہ وہ یہ نماز پڑھ آیا ہے.اور نہ یہ فکر کرنا چاہیے کہ اس کی کونسی نماز فرض ہوگی کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے کہ وہ
اس کی کس نماز کو بطور فرض قبول کرتا ہے اور کس کو بطور نفل.اگر تھانہ کھڑی ہو تو پھر کوئی دوسری سنت یا نفل نمازہ نہ پڑھی جائے.اگر کوئی شخص سنتیں غیرہ
پڑھ رہا ہو اور اس دوران میں نما نہ کری ہو جائے تو اگر در صف کے اندر ہے تو وہ نماز کو ترک کر کے
Page 135
۱۲۹
فوراً جماعت میں شامل ہو جائے اور اگر علیحدہ مقتدیوں کی صف سے فاصلہ پر نما نہ پڑھ رہا ہے.اور
اُسے امید ہے کہ وہ اپنی نماز پوری کر کے امام کے ساتھ پہلی رکعت کے رکوع میں شامل ہو جائے
گا تو وہ نما نہ پوری کر سکتا ہے ورنہ نہیں.جو سنتیں نماز سے پہلے پڑھی جاتی ہیں جماعت میں شامل
ہونے کی وجہ سے اگر وہ رہ گئی ہوں تو جماعت کے بعد ان سنتوں کو پڑھ لیا جائے.صبح کی
سنتیں اگر رہ گئی ہوں تو فجر کی فرض نمازہ کے بعد پڑھ لی جائیں.اگر کوئی شخص کھلی جگہ میں نماز پڑھ رہا ہو تو وہ نمازی اپنی سجدہ گاہ سے کچھ فاصلے پر سترہ گاڑ
دے.یعنی اپنی چھڑی یا کوئی لکڑی نصب کر سے یا کوئی اور نشان رکھد سے تاکہ اگر کسی شخص نے
سامینہ سے گزرنا ہے تو وہ مسترا کے پرے سے گزر سے اور نمازی اور سنترہ کے درمیان
سے گزرنے کی کوشش نہ کرہ ہے.حدیث میں آتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نمانہ باہر کھلی جگہ میں پڑھاتے تو سامنے
اپنا چھوٹا نیزہ گاڑ لیتے.سفر میں بھی عمو گا آپ کا یہی طریق ہوتا.بعض اوقات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قرأت میں جب کسی ایسی آیت کی تلاوت
فرماتے جس میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح کی طرف توجہ دلائی گئی ہے یا جنت و دوزخ کا ذکر آیا ہے یا
عظمت الہی کے متعلق استفسار ہے تو ایسی صورت میں صحابہ اس کا جواب دیتے اس کی اتباع
میں آج بھی اس سنت پر عمل کیا جاتا ہے.مثلاً اگر امام سبح اسم ربك الأعلى پڑھے تو مقتدی
کسی قدر بلند آواز سے سُبحان ربی الاعلیٰ کہیں اور اگرہ تُم اِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ پڑھے تو
مقتدى اللهُم حَاسِبُنَا حِسَابًا يَسِيراً پڑھیں.یا اگر وہ اليْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْعَالَمین
پڑھے تو مقتدى بلى وانا عَلَى ذَالِكَ مِنَ الشَّهِدِينَ پڑھیں.امام نماز میں صرف اپنے لئے
دعا نہ کہ ہے.بلکہ مقتدیوں
کو بھی دعا میں شامل کرے اور ان کے لئے بھی دعا کرہ ہے.نمانه با جماعت کی حکمت
حدیث میں آتا ہے کہ نماز با جماعت سے ستائیں گنا نہ یادہ ثواب ملتا ہے.مسجد کی طرف
ہر قدم نیکی شمار ہوتا ہے.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا.نماز با جماعت کے ثواب کا اگر مسلمانوں کو
اندازہ ہو اور گھٹنوں کے بل اس کے لئے ان کو آنا پڑ سے تب بھی وہ آئیں.نماز با جماعت کے ذریعہ اجتماعی دعا کی توفیق ملتی ہے.نماز با جماعت سے
اتحاد اسلامی تنظیم اور
Page 136
اس کی اطاعت کی اہمیت واضح ہوتی ہے.علیہ السلام اور تبلیغ حق کے لئے اجتماعی کوششوں کی فکر
فروغ پاتی ہے.پھر نمانہ یا جماعت کے لئے اکٹھا ہونے سے باہمی الفت و تعاون اور ہمدردی کا
سبق ملتا ہے جسے مسلمان دن میں پانچ بار دہراتے ہیں.بار بار اکٹھے ہوتے سے ایک دوسرے
سے تعارف حاصل ہوتا ہے.پاس پاس رہنے والوں کے حالات کا علم ہوتا ہے.غریبوں اور
ضرورتمندوں کے کام آنے کے مواقع میسر آتے ہیں.مساوات عالمگیر یک جہتی اور روحانی اتحاد کی
ضرورت کا احساس بڑھتا ہے ایک محلہ یا ایک گاؤں کے رہنے والے دن میں پانچ بار نماز باجماعت
کے لئے مسجد میں اکٹھے ہوتے ہیں.پھر سارے شہر اور اردگرد کے گاؤں کے لوگ ہفتہ میں ایک
بار جمعہ کے لئے بڑی مسجد میں جمع ہوتے ہیں اور سالی میں اس
کی کبھی زیادہ دور کے لوگ عید کیلئے
آتے ہیں اور عمر بھر میں ایک بار استطاعت رکھنے والے حج کے لئے مکہ مکرمہ میں جمع ہوتے ہیں
گویا اتحادا در تنظیم کے یہ مختلف مدارج ہیں جو اجتماع کی ان صورتوں میں قائم کئے گئے ہیں.بلند یا آہستہ آواز سے قرات پڑھنے کی حکمت
جیسا کہ اوپر گذر چکا ہے.بلند آواز سے پڑھی جانے والی رات کی نمازیں ہیں اور خاموشی اور
آہستہ آواز سے پڑھی جانے والی دن کی ہیں.دن کے وقت شور زیادہ ہوتا ہے امام اگر بلند آواز
سنانا چاہے تو اس پر بوجھ زیادہ پڑے گا.اس تکلیف سے بچانا ایک جسمانی حکمت ہے.روحانی حکمت یہ ہے کہ دن کے وقت نور ہوتا ہے ہر شخص دیکھے سکتا ہے اس لئے آواز سے سمجھانے
کی ضرورت نہیں.لیکن رات کو تاریخی ہوتی ہے کسی کو اندھیرے میں سوجھتا ہے کسی کو نہیں اس لئے
آواز سے سمجھانے کی ضرورت پڑتی ہے.دن کی نمازوں میں اس امر کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جب
سب کو ہدایت مل جائے تو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر کے ہدایت پر قائم رہو اور جب دنیا میں
تاریخی پھیل جائے تو ایک دوسرے کو بلند آواز سے خبر دار کرتے رہو.کیا آپ نے دن کے وقت
اکٹھے چلنے والے اور رات کے وقت اکٹھے چلنے والے مسافروں کو نہیں دیکھا.دن کو چلنے والے
مسافر ایک دوسرے کو آوازہ نہیں دیتے.رات کو چلنے والے آوازیں دیتے جاتے ہیں کوئی کہتا ہے
دیکھنا گڑھا ہے کوئی کہتا ہے بچنا کیچڑ ہے پانی ہے.پس سیری قرأت میں روحانی حکمت یہ ہے کہ سہولت اور آسانی نور کے وقت ایک دوسرے
سے تعاون کر تے ہوئے چلیں اور جب تاریخی اور باری پھیل جائے تو اس وقت صرف عمل ہی کافی نہیں
Page 137
۱۳۱
بلکہ تلقین بھی ضروری ہے اور جسم کے ساتھ نہ بان بھی شامل ہونی چاہیئے.علاوہ انہیں اس ہدایت میں اطاعت کا امتحان بھی لیا گیا ہے.کیونکہ دن ہاؤ ہو کا وقت ہے
دل بولنے کے لئے مچلتا ہے لیکن حکم ہوا کہ بولنا نہیں.رات سکون کے لئے ہے دل بالکل خاموشی کو
چاہتا ہے اس لئے ہدایت ملی کہ اس وقت خوب بلند آواز سے قرآن شریف پڑھو اور اطاعت
اہی کے گیت گاؤ.رات کی نمازوں میں سے بعض حصّہ کی قرائت بلند آواز میں کی جاتی ہے اور بعض حصہ کی خاموش
اور آہستہ.مغرب کی نماز میں دو رکعت بلند آواز سے ہیں اور ایک رکعت خاموشی سے ہے اس کی
وجہ یہ ہے کہ مغرب کے وقت ایک طرف خاموشی طاری ہو جاتی ہے اور آواز سنائی جاسکتی ہے.لیکن ساتھ ہی وہ تاریخی کی ابتداء کا وقت ہوتا ہے اور ہر حالت سے دوسری حالت کی طرف گریز کرتے
وقت اعتصاب کو ایک صدمہ پہنچتا ہے.اس لئے بلند آواز کا حصہ زیادہ رکھا اور خاموشی کا کم اور عشاء
کے وقت اور بھی زیادہ آواز کے پہنچانے میں سہولت ہوتی ہے لیکن انسان ابتدائی صدمہ سے محفوظ
ہو جاتا ہے اور اس کے مخفی بالطبع ہونے کا وقت آجاتا ہے.اس لئے اس میں دونوں حالتوں کو بر اسیر
رکھا ہے.صبح کے وقت انسان پر نیند کا غلبہ ہوتا ہے اکثر لوگ قریب میں ہی سو کر اُٹھے ہوتے ہیں
اور آواز بھی اچھی طرح سنائی جاسکتی ہے اس لئے دونوں رکعتوں میں قرأت رکھی تاکہ لوگوں میں
سستی نہ پیدا ہو اور غنودگی دُور ہو جائے.در حقیقت نماز میں یہ بتایا گیا ہے کہ انسانی روح کے کمال کے لئے دوسروں کے ساتھ تعاون،
وعظ و تذکیر اور مراقبہ یہ تینوں چیزیں ضروری ہیں.مراقبہ کا قائم مقام خاموش نمازیں ہوتی ہیں جن میں انسان اپنے مطلب کے مطابق زور دیتا ہے.وعظ تذکیر
کا نشان قرآت ہے جو انسان کو باہمی نصیحت کرنے کی طرف توجہ دلاتی ہے اور
تعاون کا نشان جماعت ہے.جماعت کے علاوہ جو سب اوقات میں مد نظر رکھی گئی ہے دوسری دونوں
کیفیتوں کو مختلف اوقات میں اللہ تعالٰی نے رکھ دیا ہے دن کے وقت کی نمازوں سے جمعہ کی نمازہ
مستثنیٰ ہے اس میں جو قرآت نماز میں بلند آواز سے پڑھی جاتی ہے وہ اس لئے ہے کہ جمعہ اجتماع اور
خاص طور پر وعظ و تذکیرا در تلقین احکام کا دن ہے اس لئے اس میں قرآت بالجہر ضروری تھی.رات کی نمانہ دن میں سے بعض میں قرأت اور خاموشی کو جمع کر دیا گیا ہے اور بعض میں صرف قرآت کو
سے لیا گیا ہے جیسے صبح کی نمازہ ہے.اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ جب کسی تنزل کی ابتداء ہوتی ہے تو
Page 138
۱۳۲
وعظ و تذکیر اور مراقبہ کے متفقہ نسخے سے قوم کی اصلاح ہوتی ہے.لوگ زور سے تازہ تازہ نکلے ہوتے
ہیں اور قلب کی حالت پر غور کرنے کے لئے تیار ہوتے ہیں.لیکن جس وقت تنزل اپنی انتہا کو پہنچ جائے
جیسے رات
کی تاریکی ہوتی ہے تو اس وقت لوگوں میں یہ مادہ نہیں رہتا کہ وہ غور کریں تو اس وقت تذکر
ا مگر خود
کو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا کی ہو وہ لوگوں
ندان قران کریم میں بھی اس زمانے کی مشق کروانا والليل ان الشقق والصبح
الى المقاس ال زبان میں تاریکی کی لائی اور میدے کے جس وجہ سے لوگوں کو اسی خطر
وبیاں اور لوگوں کو جگا.نسے والے کو نہ بادہ تو جو دینی پڑتی ہے اس لئے اس وقت میں مراقبہ
کاشتہ بنا دیا گیا اور وعظ تذکیر اور مشکی تبلیغ پر زیادہ زور دیا گیا.سری دستے و ہنر کتہ تھامے راندا اے
نماز با جماعت کے اہمت سے
الایمانیات شان میں زیادہ تو اب کی دویر کیا ہے ؟
الرمان و الریان اب لگتا ہے اس میں یہ فرض ہے کہ دست پیدا ہوتی
تاکید ہے کیا
بھی سادی ہوں اور صف سیدھی ہو اور ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوں.اس -
ال یہ ہے کہ گویا ایکاری انسان کا حکم رکھیں اور ایک کے انوار دوسرے میں حراست گوار
وہ تمیز نہیں میں خودی اور خود فرضی پیدا ہوتی ہے نہ رہ ہے.یہ خواب یا دور کھو کہ انسان میں فوت
ہے.لو
سوال : نماز کی پابندی کرانے کے لئے یہ تجویز کی گئی ہے کہ جو مرد دانستہ نماز با جماعت میں غفلت
کمر سے ایک آنہ جرمانہ ادا کر سے اور جو عورت دانستہ نماز میں غفلت کرے وہ دو پیسہ اور
جو نما نہ جمعہ میں دانستہ خفت کرہ سے اُس سے چار آنہ جرمانہ لیا جائے.جوا ہے :.جوش تو اچھا ہے اور قابل قدر ہے مگر جرمانہ بدخت ہے وہی نمازہ مفید ہو سکتی ہے
جس کے ادا کرنے میں اگر کسی قسم کی سستی ہو جائے تو خود دل اس پر جرما نہ کرے.نماز کی
غفلت روح کی قربانی سے دور ہو سکتی ہے پیسوں کی قربانی سے نہیں.آنحضرت صلی الله علیه وسط ۲۰۰ نمانہ با جماعت کے متعلق یہی فرمایا ہے کہ میرا جی چاہتا
Page 139
۱۳۳
ہے کہ ایسے شخص کا گھر جلادوں کجا یہ کہ بلکلی نماند کا تارک ہو.جو شخص جماعت کے ساتھ نمازہ
اور کرنے کی کوشش نہیں کرتا اور ہر ایک نماز اس کی جماعت سے رہ جاتی ہے اور اس
ا نہیں ستی و شخصی کے اس
داخل ہی نہیں.اس کا ظاہری علاج نصیحت ہے اور وغطہ ہے اور بانی علاج دعا بہت
جو اس سے بھی نہ مجھے خلیفہ وقت سے اجازت سے کہ اسے اپنی جماعت سے الگ
کر دینا چاہیئے.نمازہ اسلام کا ایک رکن ہے فوج میں لنگڑے آدمی نہیں رکھتے جاتے لیے
سوال : بعض اوقات صبح کی نماز ایسے وقت میں ہوتی ہے کہ معلوم ہوتا ہے بھی صبح نہیں ہوئی ایسی
صورت میں جماعت کے ساتھ شامل ہونے یا نہ ہونے کے بارہ میں کیا حکم ہے؟
جواب : - آخر دوسرے لوگ وقت کجھ کر ہی نماز پڑھتے ہوں گے اور یوں ہی اپنی نمانہ کو ضائع نہیں
کرتے ہوں گے.اس واسطے ایک شخص کو اپنی رائے باقی جماعت کی رائے پر قربان کر دینی
چاہیے.اور علیحدگی نہیں اختیار کرنی چاہیے.حدیث میں آتا ہے یہ
من فارق الجماعة شبرا فيموت ميتة جاهلية :
د بخاری کتاب الفتن باب قول النبی صلی اللہ علیہ ولکم مستوردون بعدی امورات جلد
Page 140
امام الصلوة کا تقرر
والے :- کیا امام کا تقریر مرکنہ اسلام کے دائرہ اختیار میں ہے ؟
جوا ہے :.امام کے فقر کا اختیار خلیفہ وقت یا اس کے مقرر کردہ نمائندہ کو ہے.شروع سے ہی نظام
اسلامی اسی طرح پر رائج رہا.جو والی یا امیر مرکز سے مقرر کر کے بھجوایا جاتا ہے وہ امام الصلواة
بھی ہوتا ہے.ہاں بعض اوقات ایسا بھی ہوا ہے کہ کسی جگہ ولایت اور امامت کے لئے دو
الگ الگ آدمی بھجوائے گئے.اسی طرح ائمہ کو حکومت کی طرف سے باقاعدہ تنخواہیں دی
جاتی تھیں.اگر ان کے تقری کا اختیار مرکز کو نہ تھا تو مرکز نے انہیں تنخواہیں دینے کی ذمہ داری
کس بنا سیر لی.علامہ ابن جوزی لکھتے ہیں :-
بنا پر.عن الحسن رحمة الله عليه ان عمر و عثمان بن عفان رضی الله.عنهما كانا يرزقان الأئمة والمؤذنين والمعلمين والقضاة
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیرہ کو مدینہ بھجوایا تا کہ وہ لوگوں کو قرآن کریم
پڑھائیں اور نمازہ کی امامت کرائیں.چنانچہ لکھا ہے :-
تما انصرت القوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم یعنی
ليلة العقبة بحث معهم مصعب بن عمير ثم هَاجَدَ
الى المدينة بعد العقبة الاولى ليعلم القرآن ويصلى بهمه
الغرض تمام فقہاء امام کے تقریر کو مرکزہ اسلام کے اختیارات میں شمار کرتے ہیں نیز اس
بات کی تصریح کی گئی ہے کہ اگر کہیں امام وقت جائے اور وہاں اس کا نائب بھی ہو تو امام
وقت کو نماز کی امامت کہ انے کا زیادہ حق ہوگا.چنانچہ فقہ کی مشہور کتاب المغنی لابن قدامہ
میں لکھا ہے :.ان دخل السلطان بلد اله فيه خليفة فهو احق من خليفته
لان ولايته على خليفته وغيره له
: سيرة معمر بن الخطاب ملا : ١٥٢- اسد الغابـ
-1
149
: : المغنی لابن قدامه من :
Page 141
۱۳۵
بہر حال اسلامی مساجد کے نظام میں یہ امر تسلیم شدہ ہے کہ امام الصمون کے مقریہ کرنے
کا اختیار خلیفہ وقت یا اس کے نمائندہ کو حاصل ہے.اجر تے پرامام الصلوۃ مقرر کرنا
سوال : - ایک مسجد کے امام الصلوۃ ہیں انکو کچھ معاوضہ دیا جاتا ہے تاکہ مسجد آباد رہے.اس بارہ
میں شرعی ہدایت کیا ہے ؟
جوا ہے :.حضور علیہ الصلواۃ نے فرمایا.خواہ احمدی ہو یا غیر احمدی جو روپیہ کے لئے نماز پڑھتا ہے اس
کی پروا نہیں کرنی چاہیئے.نماز تو خُدا کے لئے ہے اگر وہ چلا جائے گا تو خدا تعالیٰ ایسے آدمی
بھیج دے گا جو محض خُدا کے لئے نماز پڑھیں اور مسجد کو آباد کریں.ایسا امام جو محض لالچ کی وجہ
سے نماز پڑھتا ہے.میرے نزدیک خواہ وہ کوئی ہو احمدی ہو یا غیر احمدی اس کے پیچھے نماز
نہیں ہو سکتی امام افقی ہونا چاہیئے.1
امام الصلواۃ مقرر کرنے کے شرائط
امام ایک متقی پرہیز گارہ مائع مسلما کو بنانا چاہئیے.وہ خدا کا ہو اور خدا کے لئے کام کر رہے
نفس کی موٹی یا پیشہ ورانہ ذہنیت اُس میں نہ ہو کسی ایسے شخص کے پیچھے نمانہ نہ پڑھی جائے.جی بعیت نہ کی ہو اور نظام سے منسلک نہ ہو.کیونکہ ارشاد امامکم منکم کا یہی تقاضہ ہے.بعض ائمہ دین سالہا سال مکہ میں رہے لیکن چونکہ وہاں کے لوگوں کی حالت تقویٰ سے گری
ہوئی تھی.اس لئے کسی کے پیچھے نماز پڑھنا گوارا نہ کیا اور گھر میں پڑھتے رہے یہ
غسال کے پیچھے نماز
ایک شخص نے حضرت مسیح موعود علیہ السّلام سے سوال کیا کہ غسال کو پیش امام بنانا جائز ہے ؟
حضرت نے فرمایا.یہ سوال بے معنی ہے.غسال ہونا کوئی گناہ نہیں.امامت کے لائق وہ شخص ہے
جو متقی ہو.عالم باعمل ہو.اگر ایسا ہے تو غسال ہونا کوئی عیب نہیں جو امامت سے روک سکے تے
14.0
a'
الحکم اور فتاوی مسیح موعود نشوه : فتاوی احدی منت ، الحکم ۱۰ اگست تنش ، الحکم ۳۰ را پیریل نشده
الب در ۲۳ مئی عله ، البدر ۲۳ اپریل مثله : : - قنادی مسیح موعود ۲ :
Page 142
معذور امام
ال: کیا معذور
شخص امام الہ لیتے ہیں کیا ہے ؟
☐ ☐
مقبول ہو.جو شخص خود معذور ہے مثلاً کوجہ بیماری وہ رکوع و سجدہ نہیں کر سکتا تو اس کو
امام مقررہ نہیں کرنا چاہیئے.جس شخص کی امامت کو لوگ پسند نہ کرتے ہوں.اگر وہ خود امام بن کر نماز پڑھائے تو
اس کی نمازہ نہیں ہوگی.ثواب کی بجائے وہ گناہ کا مرتکب ہوگا.حدیث میں آتا ہے :-
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول ثلاثة لا يقبل الله
منهم صلوة من تقدم قومًا وهم له كارهون ورجل اتى
الصلوة دبارًا والدبار أن ياتيها بعد ان تفوته ورجل اعتبد
محررا "
ترجمہ : حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ تین شخصوں
کی نماز قبول نہیں ہوتی ، جو شخص قوم
کا امام الصلوۃ بنے حالانکہ لوگ اس کو نا پسند کرتے ہوں.دوسرے وہ شخص جو بعد از وقت نماز
پڑھنے کا عادی ہے.تیسرے وہ شخص جس نے آزاد کو غلام بنا لیا ہو اور اس سے غلاموں کی
طرح کام لیتا ہو.امام ایسے شخص کو مقرر کرنا چاہیے جو متقی ہو.مسائل نمازہ جانتا ہو.عمدہ طریق پر قرآن کرتا
ہو.اکثریت اُسے پسند کرتی ہو.سوال: - ایک شخص کا پیشاب بوجہ بڑھا پایا ہماری نکل جاتا ہے مگر نہایت نیک اور باخدا شخص
ہے.آیا ایسا شخص امام بن سکتا ہے ؟
جواب :.اصول یہ ہے کہ اگر ایک شخص تقوی اور علم میں ممتاز ہو اور امام مقرر ہو یا اسے امامت کرے
کے لئے کہا جائے تو معذور ہونے کے باوجود بھی وہ امام بن سکتا ہے اس کی امامت کسی درجہ
میں بھی مکروہ نہیں.تاہم خود ایسے شخص کو جہاں تک اس
کی اپنی مرضی کا سوز ہے امام بننے سے
بچنا چاہیے تاکہ دوسرے خواہ مخواہ وہم نہ کریں.سیرۃ المہدی میں حضرت مرزا بشیر احمد صاحب ایم.اسے لکھتے ہیں :-
ه: - سنن ابی داؤد باب الرجل يوم القدم وهم له كارهون :
Page 143
١٣
دو ڈاکٹر میر محمد اسمعیل صاحب نے مجھ سے بیان
کیا کہ ایک دفعہ کسی وجہ سے مولانا
عبدالکریم صاحب مرحوم نماز نہ پڑھا سکے.حضرت خلیفتہ ایسی اول بھی موجود نہ
تھے.تو حضرت صاحب نے حکیم فضل دین صاحب مرحوم کو نماز پڑھانے کے
لئے ارشاد فرمایا.انہوں نے عرض کیا کہ حضور تو جانتے ہیں کہ مجھے بواسیر کا
مرض ہے اور ہر وقت ریح خارج ہوتی رہتی ہے میں نماز کس طرح سے
پڑھاؤں ؟ حضور نے فرمایا حکیم صاحب آپ
کی نمازہ با وجود اس تکلیف کے
ہو جاتی ہے یا نہیں ؟ انہوں نے عرض کیا.ہاں حضور.فرمایا کہ پھر ہماری بھی
ہو جائے گی آپ پڑھائیے.خاکسار عرض کرتا ہے کہ بیماری کی وجہ سے اخراج ریح جو کثرت کے ساتھ جاری رہتا
ہے.یہ نواقض وضو میں نہیں سمجھا جاتا " ہے
نابالغ امام
سوال :.کیا ایک بچہ دوسرے بچوں کو نماز باجماعت پڑھا سکتا ہے؟
جواب : - ایک نابالغ مگر سمجھدار بچہ کی امامت جائز ہے.اس میں کوئی حرج نہیں خواہ مقتدی
بڑی عمر کے ہوں اور ان میں کوئی اچھا پڑھا لکھا نہ ہو جماعت کرانا نہ جانتا ہو لیکن چھوٹی عمر کا
بچہ سمجھدار ہو.قرآن خوب پڑھ سکتا ہو.نماز کے مسائل سے واقف ہو تو وہ نابالغ ہونے کے
یا وجود امام بن سکتا ہے.حضرت عمرو بن
سلمہ بیان کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے ایام میں میری عمر چھ سات سال کی تھی
اس زمانہ میں بڑی کثرت سے قبائل مسلمان ہو رہے تھے.ہمارے قبیلہ میں سب سے پہلے میرا
باپ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے قبیلہ کی نمائندگی میں اسلام
قبول کیا.واپس آکر اس نے لوگوں کو حضور کی ہدایات سنائیں کہ اتنی نمازیں فلاں فلاں وقت
میں پڑھی جائیں.نماز کے وقت اذان دی جائے اور تم میں سے جو زیادہ قرآن جانتا ہو وہ امام
بنے.میری عمر اگر چہ چھوٹی تھی لیکن سب سے زیادہ میں قرآن جانتا تھا کیونکہ مجھے علم کا شوق
تھا اور مسلمانوں کے جو قافلے ہمارے قریب سے گزرتے اُن کے پاس جا کر میں اُن سے قرآنِ
کریم سنتا اور یاد کر لیتا تھا.چنانچہ لوگوں نے مجھے ہی امام بنالیا.میری چادر بالکل چھوٹی تھی جب
- سيرة المهدی حصہ سوئم مالا روایت ۶۵۳
گر
Page 144
۱۳۸
یں سجدہ میں جاتا تو بے پردگی ہوتی.ایک عورت نے مزاقاً کیا.بھائیو ! پہلے اپنے امام کا
تنگ تو ڈھانکو.چنانچہ لوگوں نے مجھے قمیض بنوادی اور اس وقت قمیض پہننے کی مجھے اس قدر
خوشی ہوئی کہ بیان نہیں کر سکتا ہے
عورت اور امامت صلوة
سوال :.کیا عورت امام بن سکتی ہے؟
جواب :.عورت کے امام ہونے کا ذکر بعض حدیثوں میں آتا ہے یعنی عورت دوسری عورتوں کی امام
بن سکتی ہے.اس صورت میں بہتر ہے کہ صرف اقامت کہی جائے.اذان کی ضرورت نہیں.اس طرح امام عورت کو صف کے درمیان کھڑا ہونا چاہیئے.مرد امام کی طرح آگے کھڑی نہ
ہو.یہ امامت حسب ضرورت صرف شاذ صورتوں میں جائز ہے.اسے رواج کی شکل دیدینا
اور عورتوں کا اس طرح عادتاً با قاعدہ باجماعت نماز پڑھنا جس میں امام بھی صورت ہو مناسب
نہیں.قرون اولیٰ کے مسلمانوں میں اس کی بہت کم مثال ملتی ہے
سوال: کیا عورتیں جلسہ سالانہ کے موقع پر زنانہ جلسہ گاہ میں حضور ایدہ اللہ تعالیٰ کی اقتداء میں نمازی
جمعہ پڑھ سکتی ہیں.جبکہ لاؤڈ سپیکر کے ذریعہ آواز پہنچ رہی ہو ؟
جواب : - امام کی اقتداء کے لئے ضروری ہے کہ امام مقتدیوں سے آگے یا اُن کے برابر ہو یعنی
کسی مقتدی کی پشت امام کی طرف نہ ہو.اگر یہ صورت ممکن ہے اور آواز کا رابطہ قائم ہے تو
اتنی دوری اور فاصلہ کے باوجود عورتیں نماز جمعہ ادا کر سکتی ہیں اور یہ فاصلہ جو مردانہ جلسہ گاہ
اور زنانہ جلسہ گاہ میں ہے اقتداء اور نمانہ کے جواز میں حارج نہیں.امام الصلوۃ پر اعتراض
سوال : اگر کسی کو امام الصلوۃ پر اعتراض ہو تو کیا کر رہے ؟
جواب:- اگر مقامی جماعت کے لوگ کسی شخص کو بذریعہ انتخاب اپنا امام مقرر کریں یا مرکزہ کی طرف سے
کسی کو امام الصلوۃ مقر کیا جائے تو پھر انفرادی طور پر کسی شخص کا یہ حق نہیں کر وہ اپنی کسی
ناپسندیدگی کی وجہ سے ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنے سے انکار کہ سے اور عملی اختلاف کا
اظہار کر ہے.اپنی علیحدہ نماز پڑھے.اگر وہ اس طرح علیحدہ نماز پڑھے گا تو نظام کی خلاف ورزی
شده بخاری باب مقام النبي صل الله عليه وسلم بکتر من افتح جلده مثل نيل الأوطار في كتالونيا الامامه وصفة الالم الاول ۲۳۵
Page 145
۱۳۹
کرنے والا اور اپنے نیک اعمال کو ضائع کرنے والا ہو گا.اگر کسی امام پر اعتراض ہو تو اس کی مرکز
میں شکایت کر کے اُسے امامت کے منصب سے علیحدہ کرانا چاہیئے اور پھر مرکزہ کی ہدایت
کے ماتحت دوسرا امام مقرر کیا جانا چاہیے.لیکن جب تک مرکز کوئی فیصلہ نہ کرہ سے اسی
امام کی اقتداء میں نماز پڑھنی چاہیئے جسے اکثریت نے امام الصلوۃ مقرر کیا ہے اور جس سے
امام بننے کو وہ پسند کرتی ہے.اسی طرح امام کے لئے بھی یہ ہدایت ہے کہ اگر اکثریت اس
کے پیچھے نماز پڑھنا پسند نہیں کرتی تو وہ امام نہ بنے لیے
امام کے کھڑا ہونے کی جگہ
بعض فرقوں کا عقیدہ ہے کہ نماز میں امام آگے نہ کھڑا ہو بلکہ صف کے اندر ہو کر کھڑا ہو.حضرت اقدس نے فرمایا :-
امام کا لفظ خود ظاہر کرتا ہے کہ وہ آگے کھڑا ہو.یہ عربی لفظ ہے اور اس کے
وو
معنی ہیں وہ شخص جو دوسرے کے آگے کھڑا ہو.لے
سوال : اگر امام اور مقتدی ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے ہوں تو کیا امام صف
میں تھوڑا سا آگے کھڑا ہو ؟
جوار ہے.اگر امام اور مقتدی ایک ہی صف میں ہوں تو کوئی ضرورت نہیں کہ مقتدی پیچھے ہو.حدیثوں
سے ثابت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس کو اپنے ساتھ کھڑا کیا اور اگر
امام یہ بتانے کے لئے کہ اصل مقام اس کا آگے ہے.کچھ آگے کھڑا ہو جائے تب بھی
کوئی حرج نہیں" سے
سوال : اگر اگلی صف میں جگہ نہ ہو تو کیا پیچھے اکیلے کھڑے ہو جانا جائز ہے ؟
جواہے :- صف کے پیچھے اکیلے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی احادیث رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم میں
مخالفت موجود ہے.فرمایا :-
ان رجلا صلى خلف الصف وحده نامر النبي صلى الله عليه وسلم
ان يعيد الصلوة له
نیز دیکھیں الفضل هم دسمبر الله : ۱۹ البدر ۱۳ فروری شار : ۲۳ : الفضل دراگست شاه
ه ترمذی جلد ا م ، باب ماجاء في الصلوة خلف الامام وحدة :
-
Page 146
۱۴۰
تاہم ہر حکم اپنے ساتھ کچھ مستثنیات بھی رکھتا ہے.پس اگر مجبوری ہو اور اگلی صف میں سے
کسی کو پیچھے لاکر اپنے ساتھ کھڑا کرنا مشکل ہو مثلاً سب تشہد میں بیٹھے ہیں اور کسی کو اٹھانا مشکل
ہے یا پیچھے اتنی جگہ نہیں کہ دوسرے کو کھڑا کر سکے تو پھر بامر مجبوری اکیلے بھی پیچھے کھڑا ہو سکتا
ہے.چنانچہ لکھا ہے:.عدم الأمر بالاعادة على من فعل ذالك بعذر
یعنی اگر کسی عذر کی وجہ سے پیچھے اکیلے کھڑے ہونے پر مجبور تھا تو نماز دہرانے کی ضرورت
نہیں.اس کی نماز ہو گئی.امام مالک اور علماء حنفیہ کا بھی یہی مسلک ہے.لہ
سوال : کیا ضرورت کے وقت مسجد کے ستونوں کے درمیانی دروں میں نمازہ کے لئے صف
بنائی جا سکتی ہے ؟
جواب: - حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے پیل پایوں کے بیچ میں ریعنی ستونوں کے درمیانی در
میں کھڑا ہونے کا ذکر آیا کہ بعض احباب ایسا کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا :-
" اضطراری حالت میں تو سب جائز ہے.ایسی باتوں کا چنداں خیال نہیں کرنا
چاہئیے.اصل بات تو یہ ہے کہ خدا کی رضامندی کے موافق خلوص دل کے ساتھ
اس کی عبادت کی جائے.ان باتوں کی طرف کوئی خیال نہیں کرتا " کے
امام مقتدیوں کا خیال رکھے
سوال : اگر امام الصلوة قرأة بہت لمبی کرے یا سجدہ لمبا کر سے نماز بہت لمبی پڑھائے تو کیا ہدایت
ہے؟
جوا ہے :- حضرت معاذ بن جبل کا واقعہ ہے.حضرت معاذ بن جبل کے واقعہ سے اس بارہ میں
ہدایت مل سکتی ہے.اور وہ واقعہ یہ ہے:.عنء مرو قال سمعت جابر بن عبد الله قال كان معاذ بن جبران
يصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع نيوه قومه
فصلى العشاء نقرأ بالبقرة فانصرف الرحيل فكان معاذ يتال
منه فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال فشان فتان نشان
ثلاث مراد......وامره بسورتين من اوسط المفصل - ته
TAD
له نيل الأوطار : له البدر ۱۳ فروری شنشله سه : بخاری کتاب الصلوة باب اذا طول الامام وكان :
للرجل حاجة فَخَرَجَ وصلى من :
Page 147
۱۴۱
یعنی حضرت جابر کہتے ہیں کہ معاذ بن جبل کا طریق یہ تھا کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
نماز پڑھ کر اپنے قبیلہ میں جاتے اور پھر وہاں اپنے قبیلہ کے لوگوں کو نماز با جماعت پڑھاتے.ایک
بار عشاء کی نماز میں انہوں نے پوری سورۃ بقرہ پڑھ ڈالی.ایک آدمی لمبی قرأت سے اکتا گیا اور
درمیان میں نماز چھوڑ کر چلا گیا.حضرت معاذ نے اُسے برا بھلا کہا کہ تم نے یہ منافقانہ حرکت کی
ہے.اس جھگڑے کی شکایت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہوئی تو آپ حضرت
معاذ پر سخت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ اس طرح لوگوں کو فتنے اور آزمائش میں نہ ڈالو.عام
طور پر آخری پارہ کے نصف آخر کی درمیانہ درجہ کی سورتیں پڑھا کرو.ایک اور روایت ہے :-
قال قيس اخبرني ابو مسعود ان رجلاً قال والله يا رسُول الله
انى لا تأخر عن صلاة الغداة من اجل فلان مما يطيل بنا نما
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظة اسد غضبًا
منه يومئذ ثم قال ان منكم منفرين فايكم ماصلي بالناس
فليتجوز فان فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة - له
یعنی ابو مسعود بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
شکایت کی کہ فلاں آدمی لمبی نماز پڑھاتا ہے اس لئے میں صبح کی نماز میں شامل نہیں
ہوتا.کیونکہ میرے کام کاج کا حرج ہوتا ہے.راوی کہتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کو میں نے وعظ کے دوران کبھی اتنا ناراض ہوتے نہیں دیکھا جتنا اس
شکایت پر آپ ناراض ہوئے.آپ نے فرمایا کہ تم میں سے بعض عبادت سے
نفرت دلانے پر عمل پیرا ہیں جو تم میں سے نماز پڑھائے وہ ہلکی نمازہ بڑھائے لمبی
نہ کرے کیونکہ پیچھے مقتدیوں میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں.کمزور ، بوڑھے ،
کام والے تمہیں سب کا خیال رکھنا چاہیئے.ایک دفعہ حضرت اقدس کی خدمت میں سوال پیش ہوا کہ ایک پیش امام ماہ رمضان میں
مغرب کے وقت لمبی سورتیں شروع کر دیتا ہے.مقتدی تنگ آتے ہیں کیونکہ روزہ کھول کر دکھانا
کھانے کا وقت ہوتا ہے.دن بھر کی بھوک سے ضعف لا حق حال ہوتا ہے.بعض ضعیف ہوتے ہیں
اس طرح پیش امام اور مقتدیوں میں اختلاف ہو گیا ہے.بخاری کتاب الاذان باب تخفيف الامام في القيام الخ منه جلد اول
Page 148
۱۴۲
حضرت اقدس نے فرمایا.کہ
پیش امام کی اس معامہ میں غلطی ہے.اس کو چاہیے کہ مقتدیوں کی حالت کا لحاظ رکھے
اور نمازہ کو ایسی صورت میں بہت لمبا نہ کر سے لے
امام کا انتظار
سوال :.امام کے آنے میں کچھ دیر ہو جائے تو کیا ایک شخص اکیلا نماز پڑھ سکتا ہے ؟
جو اہے :- نماز مل کر پڑھنے کا حکم ہے.یعنی یہ کہ اکٹھے ہو کر با جماعت پڑھو.اب اگر امام کو
آنے میں دیر ہو جائے اور کوئی شخص اکیلا نماز پڑھ لے تو اس کے لئے ہر گز جائز نہیں
ہے.شریعت نے ہر نماز کے لئے وقت کا جو اندازہ مقررہ کیا ہے کہ فلاں وقت
سے لے کر فلاں وقت تک نمازہ ہو سکتی ہے.اس کا یہی مطلب ہے کہ اگر تھوڑی
دیہ آگا پیچھا ہو جائے تو کوئی حرج نہیں اگر یہ مد نظر نہ ہوتا تو شریعت میں خاص وقت
مقرر کر دیا جاتا کہ میں فلاں وقت پر فلاں نماز ادا کر د جگر ایسا نہیں کیا گیا " ہے
سوال :.نمازیوں کے آنے کا انتظار ؟
جواب: - اصولاً یہ بات درست ہے کہ نماز با جماعت کے لئے نمازیوں کے جمع ہونے کا انتظار کیا
جائے تا کہ جماعت میں کثرت سے لوگ شریک ہو سکیں.حدیث میں آتا ہے کہ جتنے زیادہ نمازی
ہوں اتنا زیادہ ثواب ملتا ہے.لیکن دوسری طرف آجکل کی مصروفیت اس بات
کی مقتضی ہے
کہ زیادہ دیر تک لوگوں کو نہ روکا جائے تاکہ اُن میں اکتاہٹ پیدا نہ ہو.اور زمانہ کے نئے آنے
میں جو بشاشت ہے اُس میں کمی نہ آئے.اس مصلحت کے پیش نظر نمازوں کے لئے آجکل وقت
مقریہ کہ دیا جاتا ہے کہ فلاں نماز فلاں وقت ہوگی.عام حالات میں اس کی پابندی کرنی چاہیئے.اس کا
ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کو وقت کی پابندی کی عادت پڑے گی اور اس طرح وہ دوسروں کا وقت
ضائع کرنے کا موجب نہیں نہیں گئے.تاہم یہ ایک انتظامی امر ہے شرعاً ایسی پابندی ضروری
نہیں کہ وقت کو آگے پیچھے نہ کیا جاسکے.اگر امام الصلوۃ مناسب خیال
کریں کہ نمازی تھوڑسے آئے
ہیں اور مزید انتظارہ کہ لیا جائے تو ان
کا یہ فیصلہ جائے اعتراض نہیں بنا چاہیے اور کسی ایک کو
اس پر شدید معترض نہیں ہونا چاہیے.نیز اس امر کا تعلق منتظم کی قوت تمیزی سے بھی ہے حالات
کے مطابق وہ اپنی صوابدید پر فیصلہ کر سکتا ہے کہ زیادہ لوگوں کے آنے کے لئے انتظار مناسب
نه: البدر ۳۱ اکتوبر نشر : ۱۹ - الفضل ۳ جولائی ۳ :
Page 149
۱۴۳
کر ہے گا یا موجودہ نمازیوں کی اکتاہٹ کے پیش نظر وقت پر ہی نماز پڑھ لینی چاہیئے.جو مصلحت کا
تقاضا ہو اُس کے مطابق عمل کیا جائے.سوال ہے.اگر امام الصلوۃ تنہا نماز پڑھ لے اور بعد میں مقتدی آجائیں تو یہ ضروری ہے کہ وہی امام ان مقتدیوں
کو نماز پڑھائے یا اس کی اجازت سے دوسرا شخص بھی جماعت کہ اسکتا ہے؟
جوا ہے : اگر مقتدیوں میں کوئی پڑھا لکھا شخص ہے جو جماعت کہ اسکتا ہے تو پھر بہتر یہی ہے کہ دوسرا
شخص ہی نماز پڑھائے کیونکہ اسلام میں برہمنیت اور پادریت کی کوئی گنجائش نہیں.البتہ اگر
مقتدیوں میں کوئی ایسا شخص نہیں جو امامت کرانا جانتا ہو تو پھر اصل امام جو مانہ پڑھ چکا ہے وہی
نمانہ پڑھا سکتا ہے.ایسا کر نے میں کوئی حرج نہیں.بعض صحابہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
اقتداء میں اپنی نماز پڑھنے کے بعد اپنے محلہ کی مسجد میں آکر نماز پڑھاتے تھے.سوال ہے :.ایک شخص اپنے طور پر عشاء کی نماز اور وتر پڑھ چکا ہے.پھر جماعت کھڑی ہو گئی ، کیا وہ
جماعت میں شامل ہو سکتا ہے؟
جواہے :.ایسا شخص جماعت میں شامل ہو سکتا ہے.اس میں کوئی حرج نہیں کیونکہ حدیث سے اس کا
جوانہ ثابت ہے
فصل الصلوة لوقتها ثم ان أقيمت الصلوة فصل معهم فانها
زيادة خيريه
البتہ ایسا کرنے والا وتر دوبارہ پڑھے.روایت میں آتا ہے :
، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخِرَ صَلا تكم بالليل وتراه
دوسری جماعت
سوال : مسجد میں مقررہ وقت پر نماز با جماعت پڑھی جا چکی ہے تو کیا اسکے بعد آنے والے افراد علیحدہ
علیحدہ نماز پڑھیں یا وہ باجماعت نماز پڑھ سکتے ہیں ؟
جو ا ہے :.ایک باقاعدہ مسجد دعام گذرگاہ یا بازار میں نہ ہوں میں اگر ایک دفعہ نماز با جماعت ہو چکی ہو تو
بعد میں آنے والے لوگ اپنی علیحدہ نماز پڑھیں، تاہم حسب ضرورت وہی نماز با جماعت بھی پڑھ
سکتے ہیں.حضرت اقدس فرماتے ہیں :-
اس میں کچھ حرج نہیں حسب ضرورت اور جماعت بھی ہو سکتی ہے.سے
لے مسلم باب كرابسته تأخير الصلوة عن وقتها ص ۲۳ مصری :
۲۸۹
: مسلم باب صلاة الليل مثنى مثنى والموتر ركعت من آخرالليل ما جزا مصری ، بخاری کتاب الوتر باب يجعل آخر صلواته وتر
-
ا جلد اول : ۱۹۳ - البدر ارحون علاء ، فتادی ص۲۳ :
Page 150
۱۴۴
البتہ اگر پہلی جماعت میں شامل ہونے میں عمد استی کی تو پھر دوسری جماعت مکروہ ہوگی کیونکہ وہ
بلا ضرورت ہے.حضرت خلیفہ اسیح الثانی فرماتے ہیں:
در دوبارہ جماعت منع نہیں ہے البتہ ناپسندیدہ ہے اور وہ بھی مسجد میں مکروہ ہے
کیونکہ اس طرح الگ الگ نمازیں ہونے لگیں تو چند آدمی آئیں اور نماز پڑھیں
چل دیں اور پھر چند اور آئیں اور جماعت کر کے چلے جائیں تو اس طرح جماعت کی
اصل غرض جہ ہے وہ مفقود ہو جاتی ہے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس
کو نا پسند فرمایا ہے.لے
سابقہ ائمہ میں سے امام اعظم ، امام مالک، امام شافعی ، امام احمد غرض چاروں امام
بلا ضرورت تکرار جماعت کو نا پسند کرتے ہیں.ہے
سوال : کیا نماز کھڑے ہوتے ہی سنتیں وغیرہ چھوڑ کر فورا جماعت میں شامل ہو جانا چاہیے یا تھوڑی سی
تعقید نماز پوری کر کے انسان پہلی رکعت کے رکوع تک شامل ہو جائے ؟
جوات :.حدیث میں ہے : - اذا اقیمت الصلوۃ فلا صلوة الا المكتوبة.كه جب نماز با جماعات
شروع ہو جائے تو پھر کوئی اورنماز جائز نہیں رہاں اگر کوئی اس کی پہلی فرض نمازہ رہتی ہو تو جماعت
بدن شامل ہونے کی بجائے پہلے وہ نماز پڑھے ) اس حدیث کو بخاری کے سوا باقی سب ائمہ حدیث
نے بیان کیا ہے.(۲) موطا کی روایت ہے:.خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اقيمت الصلوة فرأى
ناسا يصلون ركعتي الفجر فقال اصلوتان مگا و نهی ان تصليا
اذا اقيمت الصلوة کے
که نماز فجر کی اقامت کہی جا چکی تھی اور حضور نمانہ شروع کرانے لگے کہ آپ نے کچھ لوگوں کو دو
رکعت سنت پڑھتے دیکھا.آپؐ نے فرمایا کیا دو نمازیں ایک وقت میں یعنی آپ نے
نماز با جماعت
کے ہوتے ہوئے دو رکعت سنت پڑھنے سے منع فرمایا.بہر حال علماء ظا ہر اس بات کے قائل ہیں کہ جب نماز کھڑی ہو تو کسی قسم کی سنتیں پڑھنی جائز
نہیں اور اگر کوئی پہلے سے سنتیں پڑھ رہا ہو اور جماعت کھڑی ہو جائے توڑ سے فوراً نماز توڑ
کر جماعت میں شامل ہو جانا چاہیئے.چنانچہ صاحب نیل الاوطار لکھتے ہیں : -
الحکم ۲۸ مارچ له سه : فقرہ مذاہب اربعه ما به سه : - نیل الاوطار ص : ۲۸ : : :
Page 151
۱۴۵
قد بالغ اهل الظاهر فقالوا اذا دخل في ركعتي الفجر او غيرها
من النوافل فاقيمت صلوٰة الفريضة بطلت الركعتان ولا
فائدة له في ان يسلم منهما ولو لم يبق عليه منهما غير
السلامة -
یعنی اہل ظاہر اس بارہ میں بڑے سخت ہیں.اُن کا کہنا ہے کہ اگر انسان سنتیں یا کوئی
نفل نماز پڑھ رہا ہو اور جماعت کھڑی ہو جائے تو اُسی وقت اس کی نماز خود بخود ٹوٹ جاتی
ہے یہاں تک کہ اسلام علیکم ورحمہ اللہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی.خواہ صرف سلام پھیرنا
ہی باقی کیوں نہ رہتا ہو.اگرچہ اس بارہ میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام یا آپ کے خلفا دو کی کوئی تفریح
نہیں مل سکی.تاہم مختلف احادیث پر غور کرنے اور ان کی ثقاہت و سند کو جانچنے کے بعد
جو صحیح صورت ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے :-
(و) اگر نماز کھڑی ہو تو پھر کسی قسم کی سنتیں شروع نہیں کرنی چاہئیں بلکہ نماز میں شامل
ہو جانا چاہیے.(ہے) اگر کوئی سنتیں پڑھ رہا ہو اور جماعت کھڑی ہو جائے اور وہ صف کے اندر ہی ہو تو
اُسے فور نماز ختم کر دینی چاہئیے.خواہ صرف تشہد ہی کیوں
نہ رہتا ہو.ہاں اگر تشہد کے ڈو
چار لفظ رہتے ہوں تو انہیں پورا کرنے اور سلام پھیر نے کی حد تک، تاخیر ممکن ہے.یاد
رکھنا چاہیئے کہ شہد سے مراد صرف التحیات ہے.ورنہ اگر درود یا دعائیں باقی ہوں تو
انہیں پورا کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ فور اسلام پھیر کہ نماز میں شامل ہو جانا چاہیئے.(ج) اگر صفوں سے الگ پیچھے یا مسجد کے کسی کونے میں صفوں سے دُور کوئی شخص سنتیں پڑھ
رہا ہے اور جماعت کھڑی ہو جائے اور اُسے اُمید ہے کہ وہ فرضوں کی پہلی رکعت کے
رکوع میں شامل ہو سکے گا تو پھر سنت کی تکمیل جائز ہے گو ضروری پھر بھی نہیں.امام
کی اتباع
سوال کیا اگر امام بیٹھ کر نمانہ پڑھائے تو مقتدیوں کے لئے کھڑا رہنا جائز ہے ؟
جواب : اگر مقررہ امام کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھا سکے تو اس کے لئے بیٹھ کر نماز پڑھانا جائز ہے.اس صورت میں مقتدی جو قیام پہ قادر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے.اس بارہ میں حضرت
ے: نیل الاوطار :
Page 152
١٤٦
خلیفہ اسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں:.دو، "چونکہ مجھے نقرس کا دورہ ہے اس لئے میں خطبہ جمعہ کھڑے ہو کہ نہیں پڑھ سکتا
رسول کریم صلی الہ علیہ وسلم کا ابتدا میں یہ حکم تھا کہ جب امام کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھا
سکے تو مقتدی بھی بیٹھ کر نماز پڑھا کریں.لیکن بعد میں خدا تعالیٰ کی ہدایت کے
ما تخت آپ نے اس حکم کو بدل دیا.اور فرمایا کہ اگر امام کسی معذوری کی وجہ سے
بیٹھ کر نماز پڑھائے تو مقتدی نہ بیٹھیں بلکہ وہ کھڑے ہو کر ہی نماز ادا کریں.پس چونکہ میں کھڑے ہو کر نما نہ نہیں پڑھا سکتا اس لئے میں بیٹھ کر نماز
پڑھاؤں گا اور دوست کھڑے ہو کہ نمازہ ادا کریں لے
(ب) ” بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہوں
تو پوری اقتداء نہیں کرتے.یہاں تک کہ امام اگر سجدہ سے سر اٹھاتا ہے تو
وہ سجدے میں پڑے ہوتے ہیں اور جب امام دوسرے سجدہ میں جانے کے
لئے تکبیر کہتا ہے تو وہ پہلے سجدہ سے سر اٹھاتے ہیں.ایسے سجدے سجدے
نہیں ہوتے کیونکہ امام کی اقتداء میں نہیں ہوتے بلکہ اپنی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں
وہ سمجھتے ہوں گئے امام تو ایک منٹ سجدہ کر کے اٹھ کھڑا ہوتا ہے ہم ڈومنٹ سجدہ
کریں گے تو زیادہ ثواب ملے گا.مگر یہ بات غلط ہے.ایسے مواقع پر امام کی اقتداء
میں ہی ثواب اور یکی ہے.سجدہ وہی ہے جو امام کے ماتحت ہو.آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا.جو لوگ امام کے پیچھے بیٹھے رہتے ہیں یا امام سے آگئے
چلے جاتے ہیں ان کا سر گدھے کے سر کی طرح بنا دیا جائے گا.پس اس سے
بچنا چاہیے.نادان اسے نیکی سمجھتے ہیں.لیکن یہ نیکی نہیں نیکی اس میں ہے کہ
جماعت کے ساتھ نماز ادا کر سے " ہے
اگر کوئی شخص ایسے وقت میں جماعت میں آکر ملا ہے کہ امام ایک یا دو رکعت پڑھا چکا ہے
تو جس وقت امام آخری سلام پھیر سے تو ایسے مسلوق کو بقیہ نماز پوری کرنے کے لئے امام
کے پہلے سلام کے ساتھ کھڑے نہیں ہو جانا چاہیئے بلکہ دوسرے سلام کہنے کے بعد کھڑے
ہونا چاہیے.ه : افضل ۳ جولائی شاه
: أ٣ - الفصل ۳ جولان ۱۹۷۳ :
Page 153
امام کی غلطی
اسلامی شریعت نے مسلمانوں
کو بتایا کہ اگر امام بھول جائے اور بجائے دو رکعت کے چار رکعت
پڑھ لے تو تم بھی اس کے ساتھ چارہی رکعت ادا کرو اور اگر وہ چار کی بجائے پانچ پڑھ نے تو تم
بھی اس کی اتباع کرو.اے
سوال :.امام دو سجدے کر کے کھڑا ہو گیا لیکن مقتدیوں کو پتہ نہ چلا اور وہ پہلے ہی سجد سے میں پڑے
رہے.سجدہ سے اٹھتے وقت پتہ چلا کہ امام دوسرا سجدہ کرنے کے بعد کھڑا ہو رہا ہے کیا
اس سے مقتدیوں کی نماز میں خلل واقع ہوگا ؟
جوا ہے :- اسی صورت میں مقتدی اپنے طور پر دوسرا سجدہ کر کے امام کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں.امام کی آواز نہ سنائی دینے کی وجہ سے جو غیر ارادی طور پر تاخیر ہوئی ہے اور مقتدی امام
کے ساتھ دوسر اسجدہ نہیں کر سکے بلکہ امام کے دوسرے سجدہ سے فارغ ہونے کے بعد
انہوں نے دوسرا سجدہ کیا ہے تو اس کی وجہ سے مقتدیوں کی نماز میں کوئی خلل نہیں پڑیگا.نہ تو انہیں دوبارہ نماز پڑھنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی سجدہ سہو کرنے کی.چنانچہ فقہ کی
مشہور کتاب فقہ مذاہب اربعہ میں ہے:.(1) اذا الميتبع الامام فيه سهدًا او بعذر فان عليه ان يقضيه
وحدة ان لم يخف نوت ما بعدة مع امامه - نه
(٢) كيفية قضاء ما فاته ان يقضيه في اثناء صلاة الامام ثم
يتابعه فيما بقي - له
(س) لا سجود على المأموم فيما يسهو فيه خلف امامه - ۵۲
نماز میں امام کے سلام سے پہلے سلام پھیرنا
سوالا.مقتدیوں نے یہ سمجھتے ہوئے کہ امام نے سلام پھیر دیا ہے غسل سے سلام کہدیا اس غلطی کا بعد میں
انہیں احساس ہوا.اب وہ کیا کریں ؟
جو اہے.حضرت اقدس نے فرمایا کہ آخری رکعت میں التحیات پڑھنے کے بعد اگر ایسا ہو جاو سے تو مقتدیوں
کی نماز ہو جاتی ہے دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں.کے
۴۲۷
الفضل ۲۱ اگست : سه فقر ندا سب اربعہ ص ۳۳ : ۳ ، ۲ فقره مدا سب اربعه صدها : شه بدر ۲ مئی شد
Page 154
۱۴۸
نماز با جماعت اور قرأة
سرا : نمازوں میں سے تین بآواز بلند پڑھی جاتی ہیں تو خاموش.علاوہ انہیں چار رکعت والی
میں دو بآواز بلند اور دو خاموش.اس میں حکمت کیا ہے ؟
جواب:.اصل جواب تو یہ ہے کہ اس فرق میں جو راز اور حکمت ہے اللہ تعالٰی نے اُسے اپنے بندوں
پر اچھی طرح واضح نہیں.فرمایا اور اطاعت اور تسلیم درضا کے پہلو کو ترجیح دی ہے کہ امنا
و صدقنا میں ہی برکت ہے.اس سوال کا دوسرا جواب یہ ہے کہ بلند آوازہ سے پڑھی جانے والی رات کی نمازیں ہیں اور
خاموشی سے پڑھی جانے والی دن کی ہیں.دن کے وقت شور زیادہ ہوتا ہے.امام اگر بلند آوازہ
سے سنانا چاہے تو اس پر زیادہ بوجھ پڑتا ہے.یہ جسمانی حکمت ہے.روحانی حکمت یہ ہے کہ دن کے وقت نور ہوتا ہے ہر شخص دیکھ سکتا ہے رات
کو تاریخی ہوتی
ہوتا
ہے کسی کو اندھیرے میں سوجھتا ہے کسی کو نہیں.دن کی نمازوں میں اس امر کی طرف اشارہ
کیا گیا ہے کہ جب سب کو ہدایت مل جائے تو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر کے ہدایت
پھیلاؤ اور جب دنیا میں تاریخی پھیل جائے تو ایک دوسرے کو بلند آواز سے خبردار کرتے رہو.کیا آپ نے دن کے وقت اکٹھے چلنے والے اور رات کے وقت اکٹھے چلنے والے مسافروں
کو نہیں دیکھا.دن کو چلنے والے مسافر ایک دوسرے کو آواز نہیں دیتے.رات کو چلنے والے
آوازیں دیتے جاتے ہیں.کوئی کہتا ہے دیکھنا گڑھا ہے کوئی کہتا ہے بچنا کیچڑ ہے پانی ہے.پس ایک روحانی حکمت یہ ہے کہ سہولت اور آسانی اور نور کے وقت ایک دوسرے سے
تعاون کرتے ہوئے چلیں اور جب تاریخی اور بدی پھیل جائے تو اس وقت صرف عمل ہی کافی
نہیں بلکہ تلقین بھی ضروری ہے.جسم کے ساتھ زبان بھی شامل ہونی چاہیے.رات کی نمازوں میں بعض حضہ کی قرآت بلند کی جاتی ہے اور بعض حصہ کی خاموش اس
میں کیا راز ہے.اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں ظاہری حکمتیں بھی ہیں اور باطنی بھی مغرب کی نماز
میں دو رکعت بلند آوازہ سے ہیں اور ایک رکعت خاموشی سے ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مغرب کے
وقت ایک طرف خاموشی طاری ہو جاتی ہے اور آواز سنائی جاسکتی ہے لیکن ساتھ ہی وہ تاریکی
Page 155
۱۴۹
کی ابتداء کا وقت ہوتا ہے اور ہر حالت سے دوسری حالت کی طرف گریز کر تے وقت اعصاب
کو ایک صدمہ پہنچتا ہے اس لئے بلند آواز کا حصہ زیادہ رکھا اور خاموشی کا کم اور عشاء کے
وقت اور بھی آواز کے پہنچانے میں سہولت ہوتی ہے لیکن انسان ابتدائی صدقہ سے محفوظ
ہو جاتا ہے اور اس کے مخلی بالطبع ہونے کا وقت آجاتا ہے اس لئے اس میں دونوں حالتوں
کو ہیرا پیر رکھا ہے.صبح کے وقت انسان پر نیند کا غلبہ ہوتا ہے اکثر لوگ قریب میں ہی سو کر اٹھے ہوتے ہیں
اور آوازہ بھی اچھی طرح سنائی جاسکتی ہے اس لئے دونوں رکعتوں میں قرأت رکھی تاکہ لوگوں میں
ستی نہ پیدا ہو اور غنودگی دور ہو.ان جسمانی وجوہ کے علاوہ روحانی وجوہ بھی ہیں.درحقیقت نماز میں ہم کو یہ بتایا گیا ہے کہ
انسانی روح کے کمال کے لئے دوسرے کے ساتھ تعاون وعظ و تذکیر اور مراقبہ یہ تین چیزیں
ضروری ہیں.مراقبہ کا قائم مقام خاموش نمازیں ہو جاتی ہیں جن میں انسان اپنے مطلب کے
مطابق زور دیتا ہے.وعظ و تذکیر کا نشان قرأت ہے جو انسان
کو باہمی نصیحت کرنے کی طرف توجہ دلاتی ہے اور
تعاون کا نشان جماعت ہے.جماعت کے علاوہ جو سب اوقات میں مد نظر رکھی گئی ہے دوسری
دونوں کیفیتوں کو مختلف اوقات میں اللہ تعالٰی نے رکھ دیا ہے ان میں دن کے وقت خاموشی
کی وجہ بیان ہو چکی ہے.دن کے وقت کی نمازوں میں جمعہ کی نماز مستثنیٰ ہے اس میں جو
قرأت بلند آواز سے پڑھی جاتی ہے وہ اس لئے ہے کہ جمعہ اجتماع کا دن ہے اس لئے اس
میں قرآت بالجہر ضروری تھی تاکہ لوگوں کو احکام اسلام کا علم ہو.رات کی نمازوں میں سے بعض میں قرأت اور خاموشی کو جمع کر دیا گیا ہے اور بعض میں صرف قرأت
کو نے لیا گیا ہے جیسے صبح کی نماز ہے اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ جب کسی تنزل کی ابتداء
ہوتی ہے تو وعظ و تذکیر اور مراقبہ کے متفقہ نسخے سے قوم کی اصلاح ہوتی ہے.ابھی لوگ نور
سے تازہ تازہ نکلے ہوتے ہیں اور قلب کی حالت پر غور کرنے کے لئے تیار ہوتے ہیں لیکن جس
وقت منزل اپنی انتہاء کو پہنچ جائے جیسے رات کی تاریکی ہوتی ہے تو اس وقت فذکران
نفعت الذکری کا زمانہ ہوتا ہے اور حکم ہوتا ہے کہ جن کو اللہ تعالے نے توفیق عطاء کی ہو وہ
لوگوں
کو جگائیں اور یہ زمانہ انبیاء کا زمانہ ہے.چنانچہ قرآن میں بھی اسی زمانہ کے متعلق فرمایا.
Page 156
16.وَالَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ : وَالصُّبْحِ إِذا النفس : ایسے زمانہ میں تاریکی کی لمبائی اور زمیند
کے نہور کی دینہ سے لوگوں کے حواس معطل ہو جاتے ہیں.ایسے زمانہ میں لوگوں کو جگانے والا ہی
جگا سکتا ہے.پس اس زمانہ میں مراقبہ کا حصہ ہٹا دیا گیا ہے
اس سوال کا ایک اور جواب یہ ہے کہ دن کے وقت شور ہوتا ہے اور طبیعتوں میں سکون
نہیں ہوتا اس لئے خدا کے کلام کے سنانے سے جو غوض ہوتی ہے کہ دلوں میں رقت پیدا ہو اور
خدا کا جلال سامنے آجائے وہ اچھی طرح پوری نہیں ہو سکتی اس لئے دن کی نمازوں میں قرأت
بالجہر نہیں ہوتی.رات کی نمازوں میں قرآت بالجہر کی یہی حکمت ہے کہ اس وقت خاموشی کا عالم ہوتا ہے.طبیعتیں سکون اور اطمینان میں ہوتی ہیں خُدا کا کلام سن کہ رقت پیدا ہوتی ہے.خدا کا کلام
تو دن کو پڑھا جائے یارات کو ہر وقت اثر پیدا کرتا ہے مگر انسانوں کے حالات مختلف ہوتے ہیں
اس لئے ایک ہی بات ایک وقت کچھ اثر رکھتی ہے اور دوسرے وقت میں کچھ اور کسی نے یہ
سچ کہا ہے." ہر سخن وقتے و ہر نکتہ مقامی دارد.اس کے علاوہ اس کا روحانی جواب بھی ہے اور وہ یہ کہ جب تاریخی کا نہ مانہ ہو اس وقت
خوب بلند آوارہ سے خدا تعالیٰ کے نام کی اشاعت ہونی چاہیئے اور روشنی کے زمانہ میں اگر کم بھی
ہو تو بھی کام چل سکتا ہے.کہ
سوال: بسم اللہ بلند آواز سے کیوں نہیں پڑھی جاتی ؟
جواب : نماز میں سورۃ فاتحہ یاکسی اور سورۃ کی قرأت کے وقت بسم اللہ بلند آواز سے پڑھنا جائز ہے
لیکن ضروری نہیں.حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور حضرت خلیفتہ اسیح الثانی بسم اللہ جہراً نہیں
پڑھتے تھے.اس لئے کسی مقتدی کا یہ خیال کرنا کہ بسم الہ جہراً نہ پڑھنے سے نمازہ ناقص ہوتی
ہے درست نہیں.بخاری اور تمیزی میں واضح حدیث موجود ہے کہ آخر الزمر حضور علیہ السلام اور
آپ کے صحابہ نمازہ میں اس موقع پر جہر الہم اللہ نہیں پڑھتے تھے.حدیث کے الفاظ یہ ہیں :-
(الف) عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم و ابا بكر وعمر
كانوا يفتحون الصلوة بالحمد لله رب العالمين له
(ب) عن انس قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والی
بكر و عمر و عثمان رضی الله عنهم فلم اسمع احدا منهم
له : الفضل ستمبر الله له الفضل 19 نومبر ۱۹۲۹ : ۳ : بخاری کتاب الصلاة هنا و تمر مدى ص :
Page 157
۱۵۱
يجهر بسمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم" له
رج ) " عن عبد الله بن مغفل قال سمعنى ابى وانا في الصلوة اقول
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فقال لى أَنَّى بنتي.قد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وهى في بكر وعمر
ومع عثمان نلم اسمع احدا منهم يقولها فلا تقلها
اذا انت صليت فقل الحمد لله رب العالمين " له
"
"
حضرت خلیفتہ المسیح اول رضی اللہ عنہ اس مسئلہ کے بارہ میں فرماتے ہیں :-
وربسم الله الرحمن الرحیم جہراً اور آہستہ پڑھنا ہر دو طرح جائز ہے.ہمارے حضرت
مولوی عبد الکریم صاحب جو شیلی طبیعت رکھتے تھے بسم اللہ جہر ا پڑھا کرتے تھے حضرت
مرزا صاحب مسیح موعود علیہ السلام جہرا نہ پڑھتے تھے صحابہ میں ہر دو قسم کے گروہ ہیں.میں
تمہیں نصیحت کر تا ہوں کہ کسی طرح کوئی پڑھے اس پر جھگڑا نہ کہو یہ سد
فاتحہ خلف الامام پڑھنا
سوال : کیا فاتحہ خلف الامام پڑھنا ضروری ہے ؟
حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سوال نہیں کرنا چاہیئے کہ فاتحہ خلف الامام نہ پڑھنے سے
نمازہ ہوتی ہے یا نہیں بلکہ یہ سوال کرنا اور دریافت کرنا چاہئیے کہ نماز میں الحمد امام کے پیچھے
پڑھنا چاہیے یا نہیں.سو ہم کہتے ہیں کہ ضرور پڑھنی چاہیئے ہونا یا نہ ہونا خدا تعالیٰ کو معلوم ہے اور
ہزاروں اولیاء اللہ حنفی طریق کے پابند تھے اور وہ خلف الامام الحمد نہ پڑھتے تھے.جب
ان کی نماز ہوئی تو وہ اولیاء کس طرح ہو گئے.چونکہ ہمیں امام حنیفہ سے ایک طرح کی مناسبت
ہے اور تمہیں ان کا ادب ہے ہم یہ فتویٰ نہیں دیتے کہ نمازہ نہیں ہوتی.اسی زمانہ میں تمام
حدیثیں مدون نہیں ہوئی تھیں اور یہ بھید چونکہ اب کھلا ہے اسی واسطے وہ معذور تھے.اور
اب یہ مسئلہ حل ہو گیا.اب اگر نہیں پڑھے گا تو بے شک اس کی نمازہ درجہ قبولیت کو نہیں پہنچے
گی.ہم بار بار اس سوال کے جواب میں کہیں گے کہ الحمد نماز میں خلف امام پڑھنی چاہیئے گیے
سوال: رکوع میں شامل ہونے سے رکعت ہوتی ہے یا نہ ؟
جوا ہے :.حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے دوسرے مولویوں کی رائے دریافت کی مختلف
اسلامی فرقوں کے مذاہب اس امر کے متعلق بیان کئے گئے.آخر حضرت اقدس نے
لے انسانی باب ترک الجهر بسم الله منا : سه ترندی باب ترک الجر بسم الله : : : : : بدر ۲۳ مئی ۱۱۳
له : - تذكرة المهدى ۲۵۳ ، فتادی مسیح موعود :
Page 158
۱۵۲
فیصلہ دیا اور فرمایا :-
ہمارا مذہب تو یہی ہے کہ لا صلوۃ الا بفاتحة الکتاب.آدمی امام کے پیچھے ہویا
منفرد ہو.ہر حالت میں اس کو چاہیے کہ سورۃ فاتحہ پڑھے.مگر امام کو نہ چاہیئے کہ جلدی
جلدی سورۃ فاتحہ پڑھے بلکہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھے تاکہ مقتدی سُن بھی لے اور اپنا پڑھ بھی ہے.یا ہر آیت کے بعد امام اتنا ٹھہر جائے کہ مقتدی بھی اس آیت کو پڑھ لے.بہر حال مقتدی
کو یہ موقع دینا چاہیئے کہ وہ سُن بھی لے اور اپنا پڑھ بھی لے.سورۃ فاتحہ کا پڑھنا ضروری
ہے.کیونکہ وہ ام الکتاب ہے لیکن جو شخص باوجود اپنی کوشش کے جو وہ نماز میں ملنے کے
لئے کرتا ہے رکوع میں ہی آکر ملا ہے اور اسی پہلے نہیں مل سکا تو اس کی رکعت ہوگئی اگر چہ
اس نے سورہ فاتحہ اس میں نہیں پڑھی کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جس نے رکوع پالیا
اس کی رکعت ہو گئی.مسائل دو طبقات کے ہوتے ہیں ایک جگہ تو حضرت رسول کریم نے فرمایا اور تاکید کی کہ نماند
میں سورہ فاتحہ ضرور پڑھیں وہ ام الکتاب ہے اور اصل نماز وہی ہے مگر جو شخص با وجود اپنی
کوشش کے اور اپنی طرف سے جلدی کرنے کے رکوع میں ہی آکر ملا ہے اور چونکہ دین کی بنا
آسانی اور نرمی پر ہے اس واسطے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی رکعت
ہوگئی.وہ سورۃ فاتحہ کا منکر نہیں ہے بلکہ دیر میں پہنچنے کے سبب رخصت پر عمل کرتا ہے.ہاں جو شخص عمد استی کرتا ہے اور جماعت میں شامل ہونے میں دیر کرتا ہے تو اس
کی نماز ہی فاسد ہے؟ لے
وال - - امام سورة فاتح پڑھ چکاہے اور پھر کوئی مقتدی کو شامل ہوا ہے وہ کیا کر ے شاو
اور سورۃ فاتحہ وغیرہ پڑھے یا قراۃ سنے.جوار ہے.مقتدی ثناء اور سورۃ فاتحہ ضرور پڑھے کیونکہ آہستہ آہستہ پڑھنا سننے کے منافی نہیں.ہاں اگر امام رکوع میں چلا گیا ہو اور مقتدی نے ابھی سورۃ فاتحہ ختم نہ کی ہو تو اس صورت میں
مقتدی بھی فوڈا رکوع میں چلا جائے اور بقیہ سورۃ فاتحہ کو رہنے دے.اسی قسم کے ایک سوال کے موقع پر مولوی عبد الکریم صاحب نے فرمایا کہ وہ رکعت اس کی
نہیں ہوگی.حضرت اقدس نے فرمایا کہ وہ رکعت اس کی ہوگئی.بھلا ہم پوچھتے ہیں کہ اگر اس کو
موقع ملتا کہ وہ الحمد پڑھ لیتا تو کیا وہ الحمد نہ پڑھتا.مولوی صاحب موصوف نے عرض کیا کہ
الحکم ۲۲ فروری شاه - فتادی مسیح موعود منه :
Page 159
۱۵۳
کیوں نہ پڑھتا.اس کا اعتقاد تو یہی ہے کہ الحمد للہ پڑھ لوں.اس پر حضرت اقدس نے
فرمایا.نیت کے ساتھ موجب ارشاد نبوی انما الاعمال بالنيات عمل کا دار و مدار
ہے اس کو اتنی مہلت نہ ملی.دل میں تو اس کا اعتقاد ہے وہ رکعت اسکی ضرور ہوگئی.اسے
جماعت سے رہی ہوئی رکعتیں کیسے پڑھے
سوال :.امام نے جب کچھ رکھتیں پڑھ لیں تو ایک شخص آکر شامل ہوا.سلام کے بعد وہ مسبوق
ان رکھتوں کو کس طرح پڑھے گا.جواہے :.امام کے سلام کے بعد جب وہ بقیہ رکھتوں کو پڑھنے کے لئے اُٹھے گا تو پہلی رکعت
میں ثناء، تعوذ، فاتحہ اور سورۃ پڑھے گا.دوسری میں فاتحہ اور سورۃ.البتہ درمیانی مشهد
کے لئے امام کے ساتھ پڑھی ہوئی رکعت بھی محسوب ہوگی.مثلاً اگر اس نے امام کے ساتھ
ایک رکعت پڑھی ہے تو امام کے سلام کے بعد اُسے ایک رکعت اور پڑھ کر درمیانی تشہد
کے لئے بیٹھنا ہوگا.اگر کوئی شخص صرف آخری تشہد میں آکر شامل ہو تو اُسے بعد میں بالکل اسی طرح نماز
پڑھنی چاہیئے جیسے وہ اکیلا نماز پڑھ رہا ہو.یعنی پہلی رکعت میں ثناء ، تعوذ ، فاتحہ اور سورۃ
دوسری رکعت میں فاتحہ اور سورۃ پڑھے گا اور باقی رکھتوں میں صرف فاتحہ.سوال :.ظہر اور عصر کی نماز کی پہلی دو رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے علاوہ کوئی دوسری سورۃ بھی پڑھ سکتا
ہے؟
جواہ: ظہر یا عصر کی پہلی دور کھتوں میں مقتدی فاتحہ کے علاوہ کوئی اور سورۃ بھی پڑھ سکتے ہیں.اس میں نہ کوئی قباحت ہے اور نہ ہی اس کا پڑھنا ضروری ہے.یعنی اجازت ہے اور پڑھنے پر
ثواب کی اُمید کی جاسکتی ہے.علامہ ابن رشد نے امام مالک کی طرف یہ قول منسوب کیا ہے
انه يستحسن القرأة فيما اسرفيه الامام.یعنی جن نمازوں میں امام آہستہ قرأۃ پڑھتا ہے ان میں مقتدی کے لئے اچھا ہے کہ وہ
بھی سورۃ فاتحہ کے علاوہ کوئی اور سورۃ پڑھے.حضرت خلیفہ المسیح الثانی نے بھی اپنی
تفسیر میں ایسا ہی لکھا ہے.حضرت امام شافعی گستری نمازوں میں مقتدی کے لئے سورۃ
کے پڑھنے کو ایسا ہی ضروری سمجھتے ہیں جیسے سورۃ فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے یہ
لها تذكرة المهدی ، فتاوی مسیح موعود من + ۲ : بداية المجتهد اس تفسیر کبیر و فاتح الناس
:
Page 160
۱۵۴
لیکن ہمارے مسلک کے مطابق یہ صرف جائز ہے ضروری نہیں.نماز میں
کسی آیت کا انکار
سوال 1- اگر امام جماعت کراتے ہوئے کسی آیت کا تکرار کرے مثلاً سورۃ فاتحہ میں اِيَّاكَ نَعبُدُو
ايَّاكَ نَسْتَعِينُ يا اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيم وغیرہ بار بار پڑھے تو کیا یہ جائز ہے؟
جوا ہے.کبھی کبھی جبکہ انسان پر خاص کیفیت طاری ہو اور وہ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْن
یا اس قسم کی کسی اور آیت کو نماز میں بارہ بار پڑھے تو یہ جائز ہے.ہاں اسے عادت نہیں بنانا
چاہیے.حضرت خلیفہ المسیح الثانی کئی بار کسی آیت کو دہرا لیتے تھے ہم نے متعدد
دفعہ آپ کو ایسا پڑھتے سُنا ہے..حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت ان تعذ بهم فانهم
عبادك کو نماز میں بہت دفعہ دہرایا.اسی طرح آپ ایک ہی سورۃ کو ایک رکعت میں بنکہ ار پڑھ
لیا کرتے تھے یہ لے
آیا تے کی ترتیب
سوال : کیا ترتیب قرآن ضروری ہے ؟
جواہے :.آیت کے اُلٹنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے.کیونکہ اس کی ترتیب براہ راست اللہ تعالیٰ کی وحی
جلی کے تابع ہے.نیز اسی مفہوم میں بعض اوقات زمین و آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے لیکن سورتوں
کی ترتیب میں یہ بات نہیں گو یہ تر تیب خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی بتائی ہوئی ہے بہر حال
نماز میں سورتوں کے آگے پیچھے پڑھنے سے نمازہ فاسد نہیں ہوتی.البتہ علماء نے اسے ناپسند
ضرور کیا ہے.چنانچہ فقہ کی کتابوں میں یہ تصریح موجود ہے کہ اگر جان بوجھ کر ایسا کیا جائے تو یہ طرزہ
مکروہ اور تعامل امت کی خلاف ورزی ہے.کہ
قرآن کریم جلد جلد پڑھنا
سوال :.ایک رکعت میں قرآن شریف ختم کرنے کا رواج ہے کیا یہ جائز ہے ؟
جواہ:.بعض لوگ جو ایک رکعت میں قرآن شریف ختم کرنا فخر سمجھتے ہیں وہ در حقیقت راف مارتے ہیں.له : كشف الغمة جلد اصلا مصری : ۰۲ : نیل الاوطار جلد ۲ منا و فقه مذاهب اریجه
Page 161
100
دنیا کے پیشہ ور لوگ بھی اپنے اپنے پیشہ پر ناز کرتے ہیں.آنحضرت صلی الہ علیہ وسلم نے کبھی اس
طریق سے قرآن ختم نہیں کیا بلکہ چھوٹی چھوٹی سورتوں پر آپ نے اکتفا کیا.لے
امام قرأۃ میں غلطی کرے
سوال : اگر فرض نماز میں امام کسی صورت کی کوئی آیت یا اس کا کچھ حصہ بھول جائے تو کیا نماز ہو جائیگی ؟
سورۃ فاتحہ کی تلاوت کے بعد نماز میں جس قدر قرآت ضروری ہے وہ ایک بڑی آیت یا کم اند کم
تین چھوٹی آیتیں ہیں اگر کوئی امام اتنی مقدار قرأت پوری کر لے تو نماز صحیح ہو جاتی ہے.اس لئے
کسی بڑی سورت سے ایک آیت چھوٹ جانے سے نماز میں کچھ ہر ج واقع نہیں ہوتا.رہا یہ کہ
اس طرح سورت کے مفہوم میں فرق آجاتا ہے تو اگر ہوا ایسا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے نسیان
اور سہو سے در گزر فرمایا ہے اور اس پر گرفت نہیں کی.لہذا اس وجہ سے بھی نماز میں کسی
قسم
کا سقم باقی نہیں رہے گا.قرآن کریم نے فرمایا ہے.فاقروا ما تيسر من القرآن کہ جتنا آسانی اور سہولت سے
قرآن کریم پڑھا جا سکے نماز میں پڑھ لو.حدیث میں ہے:-
عن إلى سعيد أنه قال امرنا ان نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر
یعنی.ابوسعید کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں حکم دیا کہ ہم نماز میں سورۃ
فاتحہ پڑھیں اور اس کے بعد جتنا حصہ قرآن کا سہولت سے پڑھا جا سکے پڑھیں.امام الصلواۃ نماز میں غلطی کرے
سوال :.امام کے پیچھے صرف عورتیں نماز ادا کر رہی ہیں.اگر امام قرآن پڑھنے میں غلطی کر سے تو کیا عورت
لقمہ دے سکتی ہے ؟
جوا ہے :.عام حکم یہ ہے کہ اگر امام دوسرے ارکان میں کوئی غلطی کرے تو مرد سبحان اللہ کہکر اور عورتیں تالی
بجا کر امام کو توجہ دلائیں ہے اور اگر وہ قرأت میں غلطی کر سے تو مقتدی اپنی یادداشت کے مطابق
لفظ کی تصحیح کر دیں.یا اگر وہ پڑھتے پڑھتے رک گیا ہے تو اگلے الفاظ بتا دیں.یہ عام حکم ہے اس
میں مرد عورت کی تخصیص نہیں.وجہ صاف ظاہر ہے کہ اگر صرف آواز پیدا کرنے سے توجہ دلائی
: بدر ۱۹ جون شاه ، فتاری سیح موعود من سے انیل الاوطار باب وجوب قرأة الفاتح جلد ٢ ص ٣ : بخارى كتاب العمل
في الصلوة باب التصفية النساء خلدا طلا :
Page 162
104
جاسکتی ہے اور اسی ضرورت پوری ہو سکتی ہے تو اسی پر اکتفاء کی جائے اور اگر اسکی ضرورت
پوری نہیں ہوتی تو آگے قدم بڑھانے یعنی زبان سے غلطی کے درست کر دینے کی اجازت ہے قرأة
میں غلطی کے درست کر دینے کی حدیث یہ ہے :-
صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فترك آية فقال له رجل
يا رسول الله اية كذا وكذا قال فهلا ذكر تنيها - له
یعنی.ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرأت میں ایک آیت بھول گئے.ایک شخص
نے نماز کے بعد توجہ دلائی تو آپ نے فرمایا.تم نے نماز میں یاد کیوں نہیں کرایا.ایسی ہی ایک روایت حضر ابن عمرض سے بھی ہے.علامہ شوکانی ان احادیث کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں :.عند نسيان الامام الآية في القرأة الجهرية يكون الفتح عليه بتذكيره
تلك الآية كما في حديث الباب وعند نسيانه بغيرها من الاركان
يكون الفتح بالتسليح للرجال والتصفيق للنساء - له
یعنی اگر تو قرأت میں غلطی ہو تو آیت بتا کہ تصحیح کر دینی چاہیئے.بتانے والا مرد ہو یا عورت
اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا.اور اگر کسی اور رکن میں غلطی ہو تو مرد سبحان اللہ کہ کر اور عور تیں
تالی بجا کہ اصلاح کی طرف توجہ دلائیں.یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ قرائت میں غلطی کی صورت میں
مقتدیوں کے لئے بتانا ضروری نہیں بلکہ امام کو چاہیے کہ اگر تو کسی قدر وہ قرائت پڑھ چکا
ہے اور آگے رک گیا ہے تو درستی کا انتظار کئے بغیر رکوع میں چلا جائے اور اگر ابتداء
میں ہی رک گیا ہے تو کوئی اور آیت یا سورت شروع کر دے.یہ بھی ایک مستحسن صورت ہے.نماز اور زبان
سوال : کیا نمازہ اپنی زبان میں پڑھنی جائز ہے ؟
جواب : خدا تعالیٰ نے جس زبان میں قرآن شریف رکھا ہے اس کو چھوڑنا نہیں چاہیئے.ہاں اپنی
حاجتوں کو اپنی زبان میں خُدا تعالیٰ کے سامنے بعد مسنون طریق اور اذکار کے بیان کر سکتے ہیں.مگر اصل زبان کو ہرگزہ نہیں چھوڑنا چاہیئے.عیسائیوں نے اصل نہبان کو چھوڑ کہ کیا پھل پایا.کچھ بھی باقی رہا ؟ سے
ه : ابو داؤد
ے نیل الاوطانہ ص : : فتادی احمدیہ مت ، فتادی مسیح موعود ص :
Page 163
104
سوال : آیت لا تقربوا الصلوة وانتم سكارى.سکاری سے مراد یہ بھی ہے کہ
معانی کا نہ جاننے والا ہو.کیونکہ حتی تعلموا ما تقولون سے یہی امر سمجھا جاتا ہے.جبس لازم آتا ہے کہ جس طرح مست یا مد ہوش آدمی نمازہ میں شامل ہو تو بے معنے ہے ایسا
ہی معانی کے نہ جاننے والا بھی نماز میں شامل ہو تو بے کار فعل کا مرتکب ہوگا ؟
جو اہے :.یہ مسلک نہ جماعت احمدیہ کا ہے اور نہ ہی امت کے سابقہ علماء میں سے کسی کا ہے یہ درست
ہے کہ ہمیں معانی آنے چاہئیں اور ان کے بغیر نماز ناقص ہے.جو شخص معانی جانتا ہے اور
ان پر غور کرتے ہوئے نماز ادا کرتا ہے اس کی نمازہ کا درجہ اس شخص کی نماز سے اعلیٰ اور ارفع
ہے.جو نمازہ میں پڑھی جانے والی آیات اور دعاؤں کے معنے نہیں جانتا لیکن اس کا یہ مطلب
ہر گز نہیں کہ جو شخص معنے نہیں جانتا وہ نماز ہی نہ پڑھے بلکہ اسلام کا حکم تو یہ ہے کہ جو شخص
الفاظ پڑھنا نہیں جانتا یا اسے یہ الفاظ یاد نہیں وہ بھی نماز پڑھے اور خاموشی سے ارکان نماز
ادا کر ہے.پھر یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ ایک شخص اچھی طرح تلفظ پر قادر ہے لیکن معنے
نہیں جانتا اسے نماز پڑھنے سے روک دیا جائے.دراصل مقصود ایک مجموعی تاثر ہے.جو
روحانیت کی بنیاد ہے اور یہ ہر سمجھدار کو جو نماز کے لئے حاضر ہوتا ہے حاصل ہوتا ہے خواہ
وہ تفصیلی معانی نہ جانتا ہو.بہر حال اس آیت کا پہلا مطلب یہی ہے کہ انسان جو کچھ پڑھے اس کے معنے بھی جانتا ہو
لیکن اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ وہ منہ سے کہہ رہا ہے اس کی صحت کا بھی اسے علم ہو
اور تلفظ میں غلطی نہ کر رہا ہو.غرض اس بارہ میں اللہ تعالیٰ نے حالات اور طاقت کے مطابق انسان
کو ذمہ دار ٹھہرایا
ہے.ریڈیویر نماز
سوال: اگر قادیان کی مسجد مبارک میں ریڈیو لگا دیا جائے تو کیا اس پر تمام دوسرے ممالک میں نماز
پڑھی جا سکتی ہے ؟
جوا ہے :.نہیں.کیونکہ اسی دو نقصان واقع ہوتے ہیں.اول اگر اس امر کی اجازت دیدی جائے
تو لوگ گھروں میں ہی نماز پڑھ لیا کریں اور مسجدوں میں نہ آئیں اور اس طرح جماعت سے جو اتحاد
Page 164
۱۵۸
اور اخوت پیدا کرنے کی غرض ہے وہ مفقود ہو جاتی ہے.دوسرا نقص یہ واقع ہو سکتا ہے کہ لوگ قرآن کریم یاد کرنا چھوڑ دیں وہ یہی خیال کر لیں
کہ ہمیں قرآن کریم یاد کرنے کی کیا ضرورت ہے.جب قادیان کی مسجد میں قرآن پڑھا جائے گا تو
ہم بھی سُن لیں گئے.اس طرح چونکہ قرآن کریم کے علم سے توجہ ہٹ جاتی ہے اس لئے اس
طریق پر نمازیں پڑھنا جائزہ نہیں.لے
غیر معمولی علاقوں میں نماز کے اوقات
(3) نماز کی فرنیت دنیا کے ہر علاقہ میں قائم ہے اور کسی علاقہ کے غیر معمولی حالات کی وجہ سے یہ
فرضیت ساقط نہیں ہو سکتی.(ب) غیر معمولی علاقوں میں نمانہ کے اوقات اندازہ سے مقرر ہوں گے اور اوقات کی پابندی لفظاً
Y
نہیں ہوگی..نماز کے اوقات کے لحاظ سے غیر معمولی علاقے.غیر معمولی علاقوں سے مراد وہ علاقے ہیں :-
(الف) جہاں دن رات چوبیس گھنٹوں سے زیادہ کے ہیں.(ب) جہاں دن رات اگرچہ چوبیس گھنٹوں کے ہیں لیکن ان میں باہمی فرق اتنا کم ہے کہ وہاں
قرآن و سنت کی رو سے نمازوں کے پانچ معروف اوقات کی واضح تفریق ممکن نہ ہو مثلاً
وہ علاقے جہاں شفق شام اور شفق صبح کے درمیان واضح امتیاز نہ ہو سکے.گویا در میان
میں غسق حائل نہ ہو.سال کے جن ایام میں یہ حرج واقع نہ ہو.ان میں معروف شرعی اوقات کی پابندی
ضروری ہو جائے گی اور ان ایام کے لئے وہ علاقے غیر معمولی قرار نہیں دیئے جائیں گے.غیر معمولی علاقوں میں نمازہ کے اوقات مندرجہ ذیل اصولی ہدایات کی روشنی میں وہاں کے مقامی
لوگ باہمی مشورہ سے متعین کریں گے.(الف) موقتہ نمازوں کے اصل اوقات وہی ہیں جو طلوع و غروب اور سورج کے دوسرے انقی
تغیرات کے مطابق عام معروف طریق سے متعین ہوتے ہیں.اس لئے جن نمازوں میں مکن
ہو اسی طریق کی پابندی کی جائے.له : المفضل ۱۳ را پریل ۱۹۳۱ ۶ :
Page 165
۱۵۹
(ب) جہاں ایسا ممکن نہ ہو وہاں مقامی حالات
کو مد نظر رکھ کر نمازوں کے اوقات چو میں گھنٹوں
کے اندر اس طرح پھیلائے جائیں کہ وہ پانچوں نمازوں کے معروف اوقات
حتی الوسع ملتے جلتے ہوں.یہ نہ ہو کہ دن یا رات کے کسی ایک حصہ میں وہ اکٹھے اور
ایک دوسرے کے بالکل قریب اکٹھے ہو جائیں ؟
Page 167
191
نماز
جمعہ
ہفتہ بھر کے سات دنوں میں سے ایک دن کا اسلامی نام جمعہ ہے.اس دن ہر شہر اور اس
کے مضافات میں رہنے والے مسلمان نہا دھو کر صاف ستھرے اور اُجلے کپڑے پہن کر اور خوشبو
لگا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لئے جمع ہوتے ہیں.جمعہ کا یہ دن ایک طرح سے مسلمانوں کی عید کا
دن ہے.اللہ تعالیٰ کی اجتماعی عبادت کے علاوہ اس بابرکت اجتماع کے ذریعہ حلقہ تعارف
وسیع ہوتا ہے.اجتماعی مقاصد کے متعلق سوچنے اور باہمی تعاون کے مواقع میسر آتے ہیں.مساوات اسلامی کے مظاہرہ کا موقع ملتا ہے.قومی اور جماعتی ضرورتوں کا پتہ چلتا ہے.وعظ و
تذکیرشن کہ رضائے الہی کی راہوں پہ چلنے کی توفیق ملتی ہے.جمعہ کی نماز کا وقت وہی ہے جو ظہر کی نماز کا ہے.البتہ امام وقت کی اشد ضروری سفر با جنگی اندازہ
کی اہم مصروفیت کے پیش نظر چاشت کے بعد اور زوال سے قبل بھی جمعہ پڑھا جا سکتا ہے.لہ
نماز جمعہ کے لئے جماعت شرط ہے.یہ نمازہ تمام بالغ تندرست مسلمانوں پر واجب ہے.البتہ
مندور نابینا - اپاہج.بیمار اور مسافر نیز عورت کے لئے واجب نہیں.ہاں اگر یہ شامل ہو جائیں
تو ان کی نمازہ جمعہ ہو جائے گی.ورنہ وہ ظہر کی نمازیں پڑھیں.: (1) عَنْ أَبِي هُرَيْرَة أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن الصلوة
نصف النهار حتى تزول الشمس الا يوم الجمعة - (مسند الثاني حيث)
(۳) عن ابي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كره الصلوة نصف النهار
الايوم الجمعة - ( ابو داؤد کتاب الصلوۃ باب الصلوة يوم الجمعة قبل الزوال جلدا مشا)
الحنابلة قالوا يبتدى وقت الجمعة من ارتفاع الشمس قدر مع و
ينتهى بضرورة ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال.ولكن ما قبل
الزوال وتت جواز يجوز فعلها فيه.وما بعد الزوال وقت وجوب يجب ايقا
عهانیه را ایقاعها فيه انقل - (كتاب الفقير على المذاهب الأربعة من جلد اول)
Page 168
۱۶۲
نماز جمعہ کا طریق
سورج ڈھلنے کے ساتھ ہی پہلی اذان دی جائے.امام جب خطبہ پڑھنے کے لئے آئے تو دوسری
اذان کہی جائے.لے
پہلے خطبہ میں تشہد اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بعد حسب موقع ایسی زبان میں ضروری نصائح
کی جائیں جس کو لوگوں کی اکثریت سمجھتی ہو.اسی خطبہ میں لوگوں کو ان کے فرائض کی طرف توجہ دلائی
جائے.اس کے بعد ایک دو منٹ کے لئے خطیب خاموش ہو کہ بیٹھ جائے.پھر کھڑے ہو کہ دوسرا
خطبہ عربی کے مقررہ مسنون الفاظ میں پڑھے.دونوں خطبے توجہ سے سننے چاہئیں.ان کے دوران
میں بولنا جائزہ نہیں کیے البتہ ضرورت پر ہاتھ یا انگلی کے اشارہ سے سے کسی کو متوجہ کیا جا سکتا ہے
ہاں امام اگر کوئی بات پوچھے تو جواب دینا چاہیئے.خطبہ ثانیہ کے بعد اقامت کہکر دو رکعت نماز با جماعت ادا کی جائے.نماز میں قرأت بالجہر
ہو.خطبہ پڑھنے والا ہی نماز پڑھائے البتہ اگر کوئی اشد مجبوری ہو تو امام وقت کی ہدایت پر کوئی
دوسرا شخص بھی نماز پڑھا سکتا ہے.جمعہ کی نماز سے پہلے اور بعد چار چار رکعت نماز سنت
پڑھی جائے.بعد میں چار کی بجائے دور کوت بھی پڑھی جا سکتی ہیں سید خطبہ کے دوران میں پہنچنے
والے شخص کے لئے مناسب ہے کہ وہ صفوں کو پھلانگ کر آگے جانے کی کوشش نہ کرتے.اگر
وہ چاہے تو جلدی جلدی دو رکعت نماز سنت ادا کر سکتا ہے.اگر کوئی شخص کسی وجہ سے آخری
قعدہ میں شامل ہو تو وہ بھی دو رکعت نمازہ پوری کمر سے کیونکہ اتحاد نیت کی وجہ سے رکھتوں کی تعداد
اتنی ہی رہے گی جنتی امام نے پڑھی ہیں.البتہ ثواب ضرور کم ہو گا.جمعہ کی نمانہ کی کوئی قضاء نہیں.اگر
ه ان الاذان يوم الجمعة كان الله حين يجلس الامام يوم الجمعة على المندر في
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والی بکر و عمر فلما كان في خلافة عثمات
و كثروا امر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث فاذن به على الزوراء فثبت الامر
على ذالك د بخاری باب التأذين عند الخطبة ما )
۱۵۸
: ابو داؤد کتاب الصلوۃ باب الکلام والامام بجلب محبت سے ابوداؤد باب الصلوة بعد الجمعة وشرح السنتهم :
109
۱۳۷
اور اور کتاب الصلاة باب تخطی درقاب الناس يوم الجمعه شه بخاری کتاب الصور باب من جاز والا امنیت ملی یک تین باستان
Page 169
144
وقت کے اندر جمعہ نہ پڑھا جا سکے تو پھر ظہر کی نماز پڑھی جائے.خطبہ ثانیہ کے مسنون الفاظ
الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ
عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا وَمَنْ يَهْلِهِ
الله فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ ، وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا
اللهُ وَنَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ - عِبَادَ اللَّهِ رَحِمَكُمُ اللَّهُ إِنَّ
الله يأمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْعَى عَنِ الْفَحْشَاءِ
والمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ، أَذْكُرُوا اللهَ يَذكُرُكُمْ
وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ الله اكبر الله
یعنی ہر قسم کی تعریف اللہ تعالیٰ کا حق ہے اس لئے ہم اس کی تعریف کرتے ہیں.اور اس سے
مدد چاہتے ہیں اور اس کی مغفرت کے طالب ہیں.اور اس پر ایمان لاتے ہیں اور اس پر توکل کرتے
ہیں.اور ہم اپنے نفس کے شرور اور اپنے اعمال کے بد نتائج سے اس کی پناہ چاہتے ہیں.جسے
اللہ تعالٰی ہدایت دے اُسے کوئی بھی گمراہ نہیں کر سکتا اور جس کی گمراہی کا وہ اعلان کر ہے اُسے
کوئی ہدایت نہیں دے سکتا.اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور ہم
گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس نے یہ درس توحید ہمیں دیا اُس کے بندے اور اس
کے رسول ہیں.اسے اللہ کے بندو تم پر اللہ رحم کرے.وہ عدل اور انصاف کا حکم دیتا ہے.اور قریبی رشتہ داروں سے اچھے سلوک کا ارشاد فرماتا ہے اور بے حیائی.بڑی باتوں اور باغیانہ
خیالات سے روکتا ہے.وہ تمہیں اس بناء پر نصیحت کرتا ہے کہ تم میں نصیحت قبول کر نیکی صلاحیت
موجود ہے.اللہ تعالیٰ کو یاد کرو وہ تمہیں یاد کرے گا.اُسے بلاؤ وہ تمہیں جواب دے گا.اللہ تعالیٰ کا باد
کرنا سب سے بڑی نعمت ہے.جمعہ کی فرضیت و اہمیت
جمعہ کے بارہ میں خاص ایک سورہ قرآن شریف میں موجود ہے جس کا نام سورۃ الجمعہ ہے اور
اس میں حکم ہے کہ جب جمعہ کی بانگ دی جائے تو تم دنیا کا ہر ایک کام بند کر دو اور مسجدوں میں جمع ہو جاؤ.لے : ابو داؤر كتاب الصلوۃ باب الرحيل يخطب على قوس ها به
Page 170
۱۶۴
اور نماز جمعہ اس کی تمام شرائط کے ساتھ ادا کرو.اور جو شخص ایسانہ کرہے گا وہ سخت گنہگار ہے.اور قریب ہے کہ اسلام سے خارج ہو اور جس قدر جمعہ کی نماند اور خطبہ سننے کی قرآن شریف میں
تاکید ہے اس قدر نماز کی بھی نہیں " اے
سوال :- جمعہ کے فرض ہونے کی کیا شرائط ہیں.بعض لوگ کہتے ہیں کہ بڑا شہر ہوں مسلمان حکومت
ہو تب جمعہ فرض ہوتا ہے شرعی حکم کیا ہے ؟
جوات : - قرآن کریم میں نماز جمعہ پڑھنے کا حکم ہے.فرمایا "إِذَا نُودِيَ لِلصَّلوة مِنْ يَوْمِ
الْجُمْعَةِ فَعَوا إلى ذكرِ اللهِ وَذَرُ و البيع - (سورۃ جمعه ۱۰)
یعنی جب تم کو جمعہ کے دن نماز (جمعہ) کے لئے بلایا جائے تو اللہ کے ذکر کے لئے جلدی جایا کرو
اور خرید و فروخت کو چھوڑ دیا کرو.نیز قرآن و حدیث میں کہیں ایسا ذکر نہیں کہ جمعہ کے فرض ہونے کے لئے ضروری ہے کہ
شہر پختہ ہو اور وہاں مسلمان حکومت ہو.اس کے برعکس طبرانی کی حدیث سے ثابت ہے کہ
شہر ہو یا گاؤں اگر وہاں نماز پڑھانے والا کوئی ایسا پڑھا لکھا آدمی ہے جو امام بن سکے تو
وہاں جمعہ واجب ہے.حدیث کے الفاظ یہ ہیں:
عَنْ اُمَّ عَبْدِ اللهِ الدَوْسِيَةِ مَرْفُوعًا الْجُمْعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى
كُل قَرْيَةٍ فِيْهَا اِمَاهُ وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا إِلَّا أَربَعَة - وَفِي
رِوَايَةٍ وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا إِلَّا ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمُ الإِمَامُ له
یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ ہر اُس گاؤں میں واجب ہے جہاں
نما ز پڑھانے
والا امام ہو خواہ مقتدی چار ہوں یا تین.حقیقت یہ ہے کہ بعض علماء نے محض احتیاط کے پیش نظر صرف وجوب کے لئے یہ شرائط
بیان کی ہیں کیونکہ جمعہ کے لئے مختلف جگہوں سے بہت سے لوگ جمع ہوتے ہیں اور خاص انتظام
کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ کوئی اختلاف اور گٹر پر پیدا نہ ہو.اسلئے کسی تنظیم ادارہ خواہ بادشاہت
کی صورت ہو یا جمہوری حکومت کی.انجمن کی ہو یا شہر کے با اثر لوگوں کی یونین جس کی لوگ باتیں
مانیں ، کا ہونا ضروری ہے.غرض یہ صرف انتظامی ہدایت ہے تاکہ امن عامہ میں کسی قسم کا خلل
-
ه: بدر مار مارچ منشار ، فتاوی مسیح موعود ملا ، الحکم ۲۴ جنوری سنشاه به
طبرانی و این عدی بحوالہ نیل الاوطار طي باب العقاد الجمعة باريع واقامتها في القرى :
Page 171
۱۶۵
واقعہ نہ ہو.ورنہ یہ کوئی لازمی شرط نہیں کہ اس کے بغیر جمعہ نہ ہو سکے.پس اگر بہولت انتظام
ہو سکے اور کسی گڑبڑ کا خطرہ نہ ہو تو جمعہ کا پڑھنا ضروری ہے خواہ شہر ہو یا کوئی گاؤں وہاں
حکومت کا کوئی یا اقتدار نمائندہ ہو یا نہ ہو.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے ہمیشہ جمہ پڑھا ہے.خواہ آپ کسی شہر
میں ہوتے یا گاؤں میں.کیونکہ یہ قرآن کریم کا حکم ہے اور قرآن کے ہر حکم پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
اور آپ کے صحابہ عمل کر تے تھے.غرض جمعہ کا پڑھنا ایک عمومی حکم ہے چنانچہ صحیح مسلم کی روایت ہے :-
إن النبي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِقَوْمٍ يَتَخَلَّفُونَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
"
هَمَمْتُ أنْ أمُرَ رَجُلاً يُصْلِي بِالنَّاسِ ثُمَّ أُخْرِقَ عَلَى
رِجَالِ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الْجُمُعَةِ بَيُوتَهُمْ " له
حضرت جابہ روایت
کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسّلام نے فرمایا :-
إِنَّ اللَّهَ لَقَدِ افْتَرَضَ عَلَيْكُمُ الْجُمُعَةَ فِي مَقَامِي هَذَا فِي
شَهْرِى هَذَا نِي مَا فِى هَذَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَرِيضَةَ مَكْتُوبَةٌ
لِمَنْ وَجَدَ إِلَيْهَا سَبِيلاً - له
ابن عباس فرماتے ہیں :-
كَانَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحِتُ عَلَى فِعْلِ الْجُمُعَةِ
في جَمَاعَةٍ اكْتَرَ مِنْ غَيْرِهَا - له
یہ تمام حوا لے اس بات کا بین ثبوت ہیں کہ جمعہ جب بھی پڑھا جائے وہ بحیثیت فرض
کے ہوگا.اس کا نفل ہونا کسی درجہ میں بھی سمجھ نہیں.اسی طرح نماز جمعہ نمازہ ظہر کا بدل ہے
جیسے جمعہ پڑھا ہے اس کے لئے ظہر کا پڑھنا بلا وجہ ہوگا اور شرعی امور میں عمل بالرائے.اور
یہ دونوں امر ایک مومن کی شان سے بعید ہیں.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل صحابہ کرام کا
دستور قرون اولی کے مسلمانوں کا اجماع اس امر پر شاہد ہیں کہ جمعہ پڑھنے کی صورت میں کسی
نے بھی ظہر کی نماز منفرد یا جماعتی رنگ میں نہیں پڑھی.کسی روایت میں بھی اس کا ذکر نہیں آتا.بلکه تمام روایتوں سے یہی پتہ چلتا ہے کہ نمانہ جمعہ سقوط ظہر کا باعث ہے.جو شخص اس امر
کا مدعی ہے کہ جمعہ پڑھنے کے بعد ظہر کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں.یا ظہر کا پڑھنا ضروری ہے
مسند احمد صات فنیل الاوطار ٣٣٥ : له كشف الغمر باب صلاة الجمعه ۲۳ : ۳ : كشف العمر ص ۳۳ :
Page 172
بار
ثبوت اس کے ذمہ ہے.یہ امر بے شک درست ہے کہ جمعہ کے وجوب کے لئے بعض ایسی شروط ہیں کہ جن کے بغیر
جمد صحیح نہیں ہوتا.مثلاً جمعہ کے لئے جماعت ایک ایسی حتمی شرط ہے کہ اس کی بغیر جمعہ درست نہ
ہوگا.ایک شخص ( فرد واحد) کے لئے جمعہ کا پڑھنا درست نہیں وہ جمعہ کی بجائے ظہر پڑھے اسکی
علاوہ بعض اور بھی مناسب شرائط ہیں جو وجوب جمعہ کا باعث بنتی ہیں لیکن ان میں سے بعض کے
فقدان کے باوجود اگر کوئی جمعہ پڑھے تو اس کا جمعہ فرض کی صورت میں ادا ہو گا اور وہ ظہر
کی نمازہ کے قائمقام بنے گا.مثلاً عورت، مریض ، مسافر اور غلام پر جمعہ واجب نہیں لیکن اگر
وہ جمعہ پڑھیں تو ان کی طرف سے یہ بحیثیت فرض ادا ہو گا اور ان کے لئے یہ جائز نہ ہوگا کہ وہ
اس کے بعد ظہر کی نماز بھی پڑھیں.سفر اور جمعہ
حضرت خلیفہ اسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :
دوستوں میں یہ اختلاف ہوا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا فتوی ہے کہ اگر
نمازیں جمع کی جائیں تو پہلی ، پچھلی اور درمیانی سنتیں معاف ہوتی ہیں.اس میں شک نہیں
کہ جب نماز ظہر یا عصر جمع ہوں تو درمیانی سنتیں معاف ہوتی ہیں یا اگر نماز مغرب اور
عشاء جمع ہوں تو درمیانی اور آخری سنتیں معاف ہو جائیں گی.لیکن اختلاف یہ کیا گیا ہے
کہ ایک دوست نے بیان کیا کہ وہ ایک سفر میں میرے ساتھ تھے میں نے جمعہ اور عصر کی
نمازیں جمع کر کے پڑھائیں اور جمعہ کی پہلی سنتیں پڑھیں.یہ دونوں باتیں صحیح ہیں.نمازوں کے
جمع ہونے کی صورت میں سنتیں معاف ہو جاتی ہیں یہ بات بھی صحیح ہے اور یہ بھی صحیح کہ رسول
کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز سے قبل جو سنتیں پڑھا کرتے تھے میں نے وہ سفر میں پڑھیں
اور پڑھتا ہوں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جمعہ کی نماز سے پہلے جو نوافل پڑھے جاتے ہیں
ان کو دراصل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے اعزاز میں قائم فرمایا ہے.سفر میں جمعہ
کی نماز پڑھنا بھی جائز ہے اور چھوڑنا بھی جائز ہے.میں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام
کو سفر میں جمعہ پڑھتے بھی دیکھا ہے اور چھوڑتے بھی دیکھا ہے.ایک دفعہ حضرت مسیح موعود
علیہ السلام ایک مقدمہ پر گورداسپور تشریف لے گئے ہوئے تھے اور آپ نے فرمایا کہ آج
Page 173
جمعہ نہیں ہوگا کیونکہ ہم سفر پر ہیں.ایک صاحب جن کی طبیعت میں بے تکلفی ہے وہ آپ
کے پاس آئے اور عرض کیا کہ سُنا ہے حضور نے فرمایا کہ آج جمعہ نہیں ہوگا.حضرت خلیفتہ ایسی اول یوں تو ان دنوں گورداسپور میں ہی تھے مگر اس روز کسی کام
کے لئے قادیان آئے تھے ان صاحب نے خیال کیا کہ شاید جمعہ نہ پڑھے جانے کا ارشاد
آپ نے اس لئے فرمایا ہے کہ مولوی صاحب یہاں نہیں ہیں اس لئے کہا حضور مجھے بھی
جمعہ پڑھانا آتا ہے.آپ نے فرمایا ہاں آتا ہوگا مگر ہم تو سفر یہ ہیں.ان صاحب نے کہا
کہ حضور مجھے اچھی طرح جمعہ پڑھانا آتا ہے اور میں نے بہت دفعہ جمعہ پڑھایا بھی ہے
آپ نے جب دیکھا کہ ان صاحب کو جمعہ پڑھانے کی بہت خواہش ہے تو فرمایا کہ اچھا آج
جمعہ ہوگا.تو میں نے حضرت مسیح موعود علیہ السّلام کو سفر کے موقع پر جمعہ پڑھتے بھی دیکھا ہے
اور چھوڑتے بھی اور جب سفر میں جمعہ پڑھا جائے تو میں پہلی سنتیں پڑھا کرتا ہوں اور
میری رائے یہی ہے کہ وہ پڑھنی چاہئیں کیونکہ وہ عام سے مختلف ہیں اور وہ جمعہ کے
احترام کے طور پر ہیں " اے
غرض جمعہ کی نمازہ ہر جگہ ہو سکتی ہے.سفر میں بھی اور حضر میں بھی.نہ اس کے لئے شہر کا ہونا
شرط ہے نہ اقامت.جو از جمعہ کے لئے صرف ایک شرط ہے کہ امن وامان اور نظم و ضبط قائم رکھا
جاسکے.لوگوں میں تمدن اور مل جل کر رہنے کا شعور ہوتاکہ زیادہ لوگوں کے جمع ہونے کی وجہ سے گڑ بڑ
کا خطرہ نہ ہو.البتہ ایک بات ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جمعہ فرض اُسی وقت ہو گا جبکہ انسان مقیم ہو تندرست
ہو حالات پر امن ہوں اور اتنے لوگ جمع ہو سکیں جو جماعت کے لئے ضروری ہیں ورنہ بصورت دیگر
جمعہ کی بجائے ظہر کی نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے.جمعہ کی نمازہ فرض ہونے کے معنے یہ ہیں کہ جمعہ ضروری ہوگا.اور اس کی بجائے ظہر کی نماز جائنہ
نہ ہوگی.امام بیہقی کی روایت ہے کہ والی بحرین نے حضرت عمریضہ کی خدمت میں سکھا کہ جمعہ کے لئے آیا
کسی خاص مقام شہر گاؤں وغیرہ کی شرط ہے یا نہیں.اس پر آپ نے اس والی کو لکھا کہ تم جہاں بھی
ہو وہیں جمعہ پڑھ سکتے ہو.یعنی اس کے لئے سفر یا حضر کی کوئی شرط نہیں.حدیث کے الفاظ یہ ہیں :-
" ان اجمعواجيت ماكنتم " کے
اسی طرح بیہقی کتاب الجمعہ میں روایت ہے :-
۱۵۴۴۲
له الفضل ۲ جنوری ئه و ۱۶ اکتوبر انتمائه له : - ازالة الخفاء منه - نقد عمر مت ،
:
Page 174
IYA
الجمعة واجبة على كل قرية وان لم يكن فيها الا اربعة " ل
ظاہر ہے کہ اس جواب کے بعد یہ بحث بے کار ہو جاتی ہے کہ شہر کی کیا حدود ہیں اور اسکی
مضافات کیا ہیں.فوجی نقل و حرکت کے دوران میں جمعہ کی نماز کے بارہ میں ہدایت یہ ہے کہ اگر فوج مع امیر عساکر
کسی ایسی جگہ پڑاؤ ڈالے ہوئے ہو جو قریہ یا شہر کا حکم رکھتی ہو اور وہاں جمعہ پڑھا جا سکتا ہو تو دیاں
فوج بھی جمعہ کی نمازہ پٹڑ ھے در نہ ضروری نہیں.ابراہیم نفی کہتے ہیں :-
كانوا لا يَجْمَعُونَ فِي الْمَسَاكِيرِ" له
کیا جمعہ کی نماز دو آدمیوں سے ہو سکتی ہے
سوال : - حضرت مسیح موعود علیہ السّلام کی خدمت میں سوال ہوا کہ کسی گاؤں میں اگر دو احمدی ہوں، یا ایک
مرد اور کچھ عورتیں ہوں تو وہ بھی جمعہ پڑھ لیا کریں یا نہ ؟
جواہ :.حضرت اقدس علیہ السلام نے مولوی محمد احسن صاحب سے خطاب فرمایا تو انہوں نے عرض کیا کہ
دو سے جماعت ہو جاتی ہے اس لئے جمعہ بھی ہو جاتا ہے.آپ نے فرمایا : ہاں پڑھ لیا کریں فقہاء نے تین آدمی تھے ہیں اگر کوئی اکیلا ہوتو وہ اپنی بیوی وغیرہ
کو پیچھے کھڑا کر کے تعداد پوری کر سکتا ہے.سے
صاحب نیل الاوطار اس بارہ میں فقہاء اسلام کے مسلک پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں :-
من قال انها تصح باثنين فاستدل بان العدد واجب بالحديث
والاجماع و راى انه لم يثبت دليل على اشتراط عدد مخصوص و
قد صحت الجماعة فى سائر الصلوات باثنين ولا فرق بينها
وبين الجماعة ولم يأت نص من رسول الله صلى الله عليه
وسلم بان الجمعة لا تنعقد الا بكذا وهذا القول
هو الراجح عندي
له :.سنن الكبرى بيهقى ميا : : - اوجز المسالک شرح موطا امام مالک ۶۳۵۰
الحکم، درمان نشاء بداره ستم له الفضل ، سورسٹی شاه ، و در جنوری ۳ار ، فتاری مسیح موعود هنا :
نیل الاوطار من باب العقاد الجمعه باربعين واقامتها في القوى +
:
Page 175
149
سوال : کیا عورتیں علیحدہ جمعہ کی نماز پڑھ سکتی ہیں اور اس کا طریق کیا ہوگا.نماز با جماعت کی صورت
میں عورت اقامت کہہ سکتی ہے ؟
جواب : آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفاء کے زمانہ میں ہمیں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی کہ
عورتوں نے الگ جمعہ یا عید کی نماز پڑھی ہو.سنت بھی یہی ہے کہ مرد اور عورتیں بل کہ ایک جگہ
جمعہ یا عید پڑھیں.تاہم عورتیں چونکہ بوقت ضرورت الگ نمازہ یا جماعت پڑھ سکتی ہیں اس لئے
اصولی طور پر باجازت مرکز حسب ضرورت کبھی کبھی ان کے لئے علیحدہ جمعہ یا عید کی نماز پڑھنے میں
بھی بظا ہر کوئی حرج نہیں بشرطیکہ اسے ایک منتقل عادت نہ بنا لیا جائے جمعہ یا نماز با جماعت
کی صورت میں عورت اقامت بھی کہہ سکتی ہے لیکن ان میں جو عورت امامت کرائے وہ صف
کے آگے کھڑی ہونے کی بجائے پہلی صف کے درمیان میں کھڑی ہوئی.اسی قسم کے ایک سوال کے
ضمن میں حضرت خلیفہ ایسیح الثانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں :
(1) اگر کوئی خاص مجبوری ہو تو اس کی بناء پر عورتوں کو علیحدہ اکٹھے ہو کہ جمعہ پڑھنے کی
اجازت دی جا سکتی ہے تا کہ اُن میں دینی روح قائم رہے لیکن اگر عام حالات میں
بھی ایسا کرنے کی اجازت دے دی جائے تو مردوں اور عورتوں میں اختلاف
پیدا ہونے کا امکان ہے.مردوں کے خیالات اور طرف جا رہے ہوں گے
عورتوں کے اور طرف اس لئے عام حالات میں حکم یہی ہے کہ مرد اور عورتیں
ایک مقام پر جمعہ کا فریضہ ادا کریں " سے
(۳) علامہ ابن قدامہ اپنی مشہور کتاب المعنی میں لکھتے ہیں :-
قال ابن المنذر ا جمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم ان
لا جمعة على النساء واجمعوا على انهن اذا حضرن فيصلين
الجمعة أن ذلك يجزى عنهن لان اسقاط الجمعة
للتخفيف عنهن فاذا تعملوا المشقة وصلوا اجزاهم
كالمريض - ۵۳
: قیام الليل باب المرأة تؤم النساء بشيخ محمد بن نصر المروزي ها :
له : - الفضل اکتوبر ۱۹ :
ه : المغنی لابن قدامه ۲ +
Page 176
160
خطبہ کھڑے ہو کر دینا چاہیے..حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا :-
ا کہ
- اسلامی سنت تو ہی ہے ک خطبہ کھڑے ہوکر پڑھ جائے کریں کچھ دنوں سے تیار ہوں
کھڑا نہیں ہو سکتا.حضور اس وقت کرسی پر بیٹھے تھے ؟
۲ - چونکہ مجھے نقرس کا دورہ ہے اس لئے میں خطبہ جمعہ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا.رسول
کریم صلی الہ علیہ وسلم کا ابتداء میں یہ حکم تھا کہ جب امام کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھا سکے تو
مقتدی بھی بیٹھ کر نماز پڑھا کریں لیکن بعد میں خدا تعالٰی کی ہدایت کے ماتحت آپؐ
نے اس حکم کو بدل دیا اور فرمایا کہ اگر امام کسی معذوری کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھائے
تو مقتدی نہ بیٹھیں بلکہ وہ کھڑے ہو کر ہی نماز ادا کیا کریں.پس چونکہ میں کھڑے ہو کہ نماز
نہیں پڑھا سکتا اس لئے میں بیٹھے کہ نماز بیٹھاؤں گا اور دوست کھڑے ہو کر نماز ادا کریں.خطبہ کا اختصار
سوال: کیا یہ ہدایت ہے کہ جتنا وقت خطبہ پر لگے اس سے آدھا وقت نماز پر صرف ہو ؟
جوا ہے :- عام اصول یہ ہے کہ خطبہ چھوٹا اور نماز لیبی ہو.سوائے اس کے کہ کوئی خاص قومی ضرورت لمبے خطبہ
کی مقتضی ہو.یا خلیفہ وقت خود ایسا کرنا ضروری سمجھیں کیونکہ خلیفہ وقت قوم کی بہبود کے مرکزی ذمہار
ہوتے ہیں اور جماعت کا وقت ان کے وقت کے تابع ہوتا ہے.یہ ایک مخصوص حق ہے جس کا
کوئی دوسراعلی الاطلاق حقدار نہیں.خطبہ کے بارہ میں عام ہدایت اس حدیث سے ظاہر ہے :-
له :- انبا جعل الامام ليؤتم به.....اذا صلى جالسًا فصلوا جلوسا اجمعون قال ابو عبد الله قال
الحميدي قوله واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا هو فى مرضه القديم ثم صلى بعد ذلك النبي
صلی الله عليه وسلم جالسا والناس خلفه قياد لم يأمرهم بالقعود وانما يؤخذ بالاخر فالاخر من
فعل النبي صلى الله عليه وسلم.(بخاری کتاب الصلاة باب انما جعل الامام ليرتم به شه)
-۲- عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه وابو بكر يصلي بالناس تملى جنب ابى بكر و الناس
ياتمون بابي بكر وابو بكر يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم (تریدی كتاب الصلوة باب اذا صلى الامام فاعدامث )
: - الفضل یکم اپریل شاه و ۳ جولائی ۹۵ائرة
1410
Page 177
141
عن عمارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ إِنَّ هُولَ
صَلوةِ الرَّجُلِ وَتَصْرَ خَطْبَتِهِ مِئَنَةٌ مِنْ فِقَهِهِ فَاطِيْلُوا الصَّلوةَ وَاقْصُرُوا
الخُطْبَة.له
حضرت خلیفہ اسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:.گو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں خطبہ کا یہی طریق تھا کہ جمعہ کی نمازہ جو دو رکعت
ہوتی ہے اس کی نسبت مختصر ہوتا مگر اس زمانہ کی ضروریات کو مد نظر رکھ کر خطبہ مبا
کیا جاتا ہے.مختصر خطبہ پڑھنا سنت یا فرض نہیں کیونکہ عرب میں رواج
تھا کہ بڑی
سے بڑی نصیحت کو چھوٹے سے چھوٹے فقر سے میں ادا کر دیتے تھے ہمارے ملک
میں لوگ لمبی گفتگو سے مطلب سمجھتے ہیں.مگر عرب میں کوشش کی جاتی تھی کہ وسیع
مضمون کو دو جملوں میں ادا کیا جائے.چونکہ خطبہ سے فرض اصلاح ہے اسلئے
ملک کی حالت کو مد نظر رکھ کر لیا خطبہ بیان
کرنا پڑتا ہے مگر جس طرح چھوٹا خطبہ پڑھنا
فرض نہیں اسی طرح لمبا خطبہ پڑھنا بھی فرض نہیں.۲
سوال : نماز جمعہ کے وقت دو خطبے ہوتے ہیں ایک تو لمبا ہو اُردو یا جونسی زبان میں چاہیں پڑھیں
دوسرا جو عربی میں ہوتا ہے.کیا دوسرا خطبہ پڑھنے کی بجائے ہم دعائیں یا صرف درود شریف
پڑھ سکتے ہیں ؟
جو ا ہے :.دوسرا خطبہ وہی مسنون عربی کا ہی پڑھنا ضروری ہے جو خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا
ہوا ہے.سے
سوال : دوسرے خطبہ میں عربی کا آدھا حصہ پڑھنے کے بعد دس پندرہ منٹ تک جماعتی کاموں
کے متعلق باتیں کرنا جائز ہے یا نہیں؟
جو ا ہے :.دوسرا خطبہ خالصتہ قرآنی آیات اور ادعیہ ماثورہ پر مشتمل ہو تو زیادہ بہتر ہے.خلیفہ وقت
کا عمل ایک استثنائی صورت ہے لیکن عام ہدایت یہی ہے کہ کوئی ضروری بات بامر مجبوری
دوسرے خطبہ میں بیان کی جاسکتی ہے.لمبی چوڑی باتیں کرنا مناسب نہیں.خلفاء راشدین
کے طریق عمل سے یہ ظاہر ہوتا ہے.اور جنہوں نے حضرت خلیفہ اینج کے خطبات جمعہ متعد بار
:-
مسلم كتاب الجمعہ باب تخفيف الصلواة والخطبه من ، ابو داؤد كتاب الصلاة باب اقتصار الخطيه من
الفضل ۱۱ جنوری ۱۹۲۳ :
ه: الفضل.ا را گست فله :
Page 178
سنے ہیں وہ اس رائے کی تائید کریں گے کہ دوسرے خطبہ کے دوران میں لمبے چوڑے اعلانات
کے لئے یہ کوئی مناسب موقع نہیں ہے.ال : خلیفہ وقت کے علاوہ اگر جمعہ یا عید میں ایک آدمی خطبہ دے اور دوسرا آدمی نمازہ پڑھائے تو
کیا یہ جائز ہے ؟
جواب حضرت خلیفہ ربیع الثانی کا اس بارہ میں جو عل تھا اس کی وضاحت مندرجہ ذیل نوٹ سے
ہو جاتی ہے :-
ر قادیان ۱۲ نبوت اسلام ہیں.آج حضور نے خطبہ جمہ پڑھا جس کے لئے حضور آرام
کرسی پر بیٹھے کہ جسے چند دوستوں نے اٹھایا ہوا تھا مسجد میں تشریف لائے اور بیٹھ کر
خطبہ ارشاد فرمایا.نماز حضور نے بیٹھ کر پڑھی جو حضرت مولوی شیر علی صاحب نے پڑھائی ہے
خلفاء کے علاوہ دوسرے افراد جو امام الصلوۃ ہوں مثلاً امیر مقامی - پریذیڈنٹ - مربی.وہ کیا
کم ہیں.اس بارہ میں حضرت خلیفہ اسیح الثالث رحمہ اللہ علیہ کی خدمت میں اس نوٹ کے ساتھ
استقصواب
کیا گیا کہ " جماعت احمدیہ کا یہ مسلک تو عملا مسلم ہے کہ خلیفہ وقت بیماری یا کسی
اور وجہ سے اگر مناسب خیال فرما دیں تو خود خطبہ جمعہ یا خطبہ عید ارشاد فرما دیں اور نماز جمعہ
عید پڑھانے کے لئے کسی اور کو حکم دیں "
خلیفہ وقت کے علاوہ کسی اور کے لئے بھی یہ جائز ہے کہ خطبہ ایک شخص دے اور نماز دوسرا
شخص پڑھائے.اس پر حضور نے فرمایا :-
صرف خلیفہ وقت اس کی ذمہ واری کے پیش نظر سے
سوال : مسجد تین منزلہ ہے بعض اوقات لاؤڈ سپیکر نہ ہونے کی وجہ سے تینوں منزلوں میں امام کی آواز
نہیں پہنچتی.کیا تینوں منزلوں میں تین امام جداجدا خطبہ دے سکتے ہیں جبکہ نماز ایک ہی امام
کے پیچھے ادا کی جائے ؟
جواب : ایک ہی مسجد میں ایک ہی وقت میں دو یا زیادہ اشخاص کا مستقلا خطبہ پڑھنا تعامل کے خلاف
ہے.اس کی بجائے بہتر صورت یہ ہے کہ خطیب اپنے نقیب مقرر کر دے جو اس کی آواز دوسری
منزل کے نمازیوں تک پہنچائیں.آخر نماز میں بھی تو اس طریق کے مطابق تکبیرات کی آوانہ
پہنچائی جاتی ہے.دوسری صورت یہ ہے کہ خطبہ بالکل مختصر کر دیا جائے.جیسا کہ مرکزی مسجد
میں حضرت امیر المومنین کی ہدایت ہے کہ خطیب دس پندرہ منٹ سے زیادہ کا خطبہ نہ دے.: الفضل ۲۹ نومبر الله و ۲ جنوری ر ہے :.رجسٹر فتادی افتا تو فتوی ملالہ مورخہ ۲۰ ۲۱ ۲
Page 179
ایک تدبیر دبشر طیکہ بات پہنچانی ضروری ہیں یہ ہو سکتی ہے کہ خطیب اپنا خطبہ سکھ سے اور
نچلی منزل والا مقرر اس وضاحت کے ساتھ یہ لکھے ہوئے الفاظ دہرائے کہ اوپر اصل خطیب
یہ باتیں بیان کر رہے ہیں.نماز جمعہ اور ریڈیو
سوالیے، کیا امام الصلوة کی موجودگی میں ریڈیو پر نشر ہونے والی نماز جمہ اور خطبہ جمعہ کی تبیع میں نماز
ادا کی جاسکتی ہے ؟
جواب : نماز با جماعت کی طرح خطبہ جمعہ اور نماز جمعہ ایک مخصوص اسلامی عبادت ہے جس کے
معین شرائط - ارکان اور آداب ہیں.جن کے بغیر یہ عبادت صحیح نہیں ہو سکتی.فرض جمعہ کی
ادائیگی کا ایک حصہ امام کا سامنے ہونا.اس کا خطبہ دینا اور اس کے بعد جمعہ کی نمازہ پڑھانا
ہے جس طرح ایک شخص لیٹے ہوئے اللہ تعالیٰ کا تصور کرے اس کی خشیت اور محبت دل میں
پیدا کرے تو اس کی اس حالت
کو نمانہ نہیں کہہ سکتے.اسی طرح موجود امام کے بغیر خطیر سکتے اور
دوسرے شہر سے آنے والی آواز کی اقتداء میں نماز پڑھنے کو نماز جمعہ ادا کرنا نہیں کہ سکتے
اسلام کی مخصوص عبادات میں اپنے طور پر کس قسم کی تبدیلی کو جائز تسلیم نہیں کیا گیا.اقامت
مسلمہ کا یہ اجتماعی فیصلہ ہے اس میں تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں.اگر کسی علاقہ کے لوگوں کو شوق
ہو کہ وہ ریڈیو پر نشر ہونے والے خطبہ جمعہ یا نماز جمعہ کو سنیں تو وہ سُن سکتے ہیں لیکن اپنا جمعہ وہ
الگ پڑھیں گے.مثلاً پہلے پروگرام شن میں بعد میں جمعہ ادا کریں.یا پہلے اپنا جمعہ پڑھ لیں بعد میں
نشر ہونے والا پروگرام سُن لیں.اس میں کوئی حرج نہیں لیکن اپنے طور پر جمعہ مسنون طریق کے
مطابق وہ بہر حال پڑھیں گے.خطبہ مختصر ہو سکتا ہے جو تشہد، درود شریف اور الحمد پر مشتمل ہو.نماز بھی الگ پڑھنی چاہیئے جو موجود امام پڑھائے.ریڈیو پر نشر ہونے والے اس قسم کے
پروگرام گننے میں انسان کی اپنی خواہش اور شوق کا دخل ہے اور اگر ازدیاد علم و ایمان مقصد
ہو تو اس کا ثواب بھی ملے گا.لیکن اس ثواب کو جمعہ کی عبادت کے ادا ہونے کے قائمقام
نہیں کہہ سکتے.سوال: خطبہ جمعہ ہو رہا ہو تو چار رکعت پڑھی جائیں یا دو.نیز خطبہ اولیٰ میں پڑھنی چاہئیں یا خطبہ
ثانیہ میں ؟
Page 180
جواب : جو شخص خطبہ کے دوران آئے وہ صرف دو رکعت نماز ادا کر سے اور وہ بھی ہلکی ہلکی.چار
رکعت ادا کرنا درست نہیں.دونوں خطبے ایک سے ضروری ہیں.دونوں آرام اطمینان اور توجہ سے گنے چاہئیں.اگر کسی نے خطبہ کے دوران میں سنتیں ادا کرنی ہیں تو وہ کسی وقت، ادا ہو سکتی ہیں.پہلے خطبہ میں بھی
اور دوسرے میں بھی.تاہم بہتر یہ ہے کہ مسجد میں آتے ہی پہلا کام دورکعت ادا کرنے کا ہے.اس کبھی بہتر صورت یہ ہے کہ دو رکعت گھر یہ ہی ادا کر کے آئے اور مسجد میں اطمینان سے بیٹھ
کہ خطبہ سنے.اے
وہ حدیث جس کی بناء پر دوران خطبہ دو رکعت سنت پڑھنے کی اجازت ہے یہ ہے :-
عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخْجُب
إِذَا جَاء أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَعْطِبُ فَلْيَد كَع ركعتين
وليتجوزفيهما - ته
خطبہ کے دوران میں بولنا
جب امام بلائے تو بولنا جائز ہے ورنہ خطبہ کے دوران میں بولنا سخت غلطی اور گناہ عظیم ہے.اگر
دعا کرنی ہو تو آہستگی سے کرنی چاہیے کہ دوسرے کو یہ دھوکا نہ لگے کہ کوئی بول رہا ہے.بعض جگہوں سے اطلاع
آتی ہے کہ لوگ خطبہ کے دوران میں بول پڑتے ہیں یہ غلطی ہے اور گناہ ہے اس کا خاص خیال رکھنا چاہیئے."
سوال :.کیا جمعہ کے روز جمعہ کے دوران پانی پینا یا جارنا یا طلب کرنا وغیرہ جائز ہے ؟
جوا ہے :.تین باتیں اصولی ہیں:.اول یہ کہ خطبہ کے وقت مکمل سکوت اختیار کیا جائے.تو جہ اور غور سے خطبہ سنا جائے یہ بات
قریب قریب واجب ہے.دوسرے.یہ کہ خطیب حتی الوسع سامعین کا خیال رکھے.انہیں اس واجب عبادت
کی انجام دہی
کے لئے زیادہ دیر نہ بٹھائے کہ وہ پریشان حال ہو جائیں.اور نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن
کے مصداق نہیں.۱۹۴۲
له الفضل ۲۳ جنوری ۹۳ و ۱۴ اکتوبر تار کے ہیلم کتاب الجمع باب المحبة والامام يخطب م *
۲۶
: - الفضل مؤرخ یار جون :
۲۹
Page 181
160
-
تیسرے یہ کہ لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَمال کی رعایت اللہ تعالیٰ نے عطاء کی ہوئی ہے
اور خطبہ چونکہ کلام اشارہ اور توجہ کے لحاظ سے بالکل ایسا نہیں جیسی نما نہ اس لئے
حسب ضرورت بامر مجبوری اس میں کوئی بات سمجھانے کے لئے انسان اشارہ کر سکتا ہے
امام سے مخاطب ہوسکتا ہے یا امام اُسے مخاطب کر سکتا ہے.حدیث میں آتا ہے.خطبہ ہو رہا تھا کہ ایک شخص آیا اور اُس نے زور زور سے کہنا
شروع کیا " يَا رَسُولَ اللهِ هَلَكَ الْمَالُ وَجَاعَ العِمَالُ فَادْعُ اللَّهَ لَنَا فَرَفَعَ
يدَيْهِ وَمَا تُرَى فِي السَّمَاءِ قَزَعَةً فَوَالَّذِى نَفْسِي بِيَدِهِ مَا وَضَعَهَا
حَتَّى ثَارَ السَّحَابُ امْثَالَ الْجِبَالِ تُمْ لَمْ يَنْزِلْ مَنْ مِنْبَرِ حَتَّى رَأَيْتُ
المطر يتتَعَادَرُ عَلَى لِحْيَتِهِ فَمُطِرْنَا يَوْمَنَا ذَلِكَ وَمِنَ الْغَدِ وَمِينَ
DAWLATEK AN وَالَّذِي يَلِيْهِ حَتَّى الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى فَقَامَ ذَلِكَ الْأَعْرَابِيُّ الغَدِ
أوْ قَالَ غَيْرُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ تَهَدَّ مَ الْبِنَاء وَفَرَقَ الْمَالُ فَادْعُ
الله لنا فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلا عَلَيْنَا فَمَا يُشِيرُ
بِيَدِهِ إِلى نَاحِيَةٍ مِنَ السَّحَابِ إِلَّا انْصَرَجَتْ وَصَادَتِ الْمَدِينَةُ مِثْلَ
الْجَوْبَة.........یعنی.اسے اللہ کے رسول مویشی ہلاک ہو گئے.فصلیں تباہ ہو گئیں باران رحمت کے
لئے دعا کیجئے.حضور نے خطبہ کی حالت میں ہی اُسی وقت دُعا کے لئے ہاتھ اٹھائے اور خُدا
کے حضور باران رحمت کے لئے دعا کی.پس اس قسم کی احادیث سے استدلال کیا جاسکتا
ہے کہ اگر زیادہ گڑبڑ کی صورت نہ ہو اور اثر مجبوری ہو تو انسان پانی پینے کے لئے جاسکتا
ہے.پنکھا کر نے کا انتظام کیا جا سکتا ہے.تاہم مقامی انتظامیہ کو اس قسم کے انتظام
کے لئے سوچ بچار کے بعد فیصلہ کرنا چاہیئے تاکہ افراد خود بخود ہے لگائی میں ایسا اقدام نہ
کریں.سوال : اگر مقتدی کو تجمعہ کی نماز میں سرف التحیات کا حصہ ملے تو کیا وہ بعد سلام امام نماز ظہر ادا
کر سے یاد دو رکعت پڑھے ؟
جواب : خطبہ جمعہ کا سننا اور جمعہ کی پوری نماند با جماعت ادا کرنا ہی اصل جمعہ ہے.جو شخص شستی کرتا
ہے اور آخری وقت میں جبکہ امام تشہد میں بیٹھا ہے آکر شامل ہوتا ہے وہ بہت بڑی بھلائی
- : : سوره بقره : ۲۸۷ ۵۲ : بخاری باب الاستسقاء في الجمعة صباب
Page 182
144
سے محروم ہے اور اپنی اپنے لئے خسران مبین کے سوا کچھ حاصل نہیں کیا.تاہم چونکہ وہ امام
کے ساتھ شامل ہو گیا ہے اس لئے امام کی نیت کے مطابق اُسے دو رکعت ہی پڑھنی چاہئیں.نہ کہ ظہر
کی چار رکعت نیه
جمعہ اور عید کا اجتماع
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا.جب جمعہ اور عید جمع ہو جائیں
تو اجازت ہے کہ جو لوگ چاہیں جمعہ کی بجائے ظہر کی نماز ادا کرلیں مگر فرمایا ہم توجہ ہی پڑھیں گے بلیک
کل بھی میرے پاس ایک مفتی صاحب کا فتویٰ آیا تھا کہ بعض دوست کہتے ہیں کہ اگر جمعہ کی
بجائے ظہر کی نمازہ ہو جائے تو قربانیوں میں ہم کو سہولت ہو جائے گی اور انہوں نے اس قسم کی حدیثیں
لکھ کر ساتھ ہی بھیجوا دی تھیں میں نے ان کو یہی جواب دیا تھا کہ اس میں کوئی شبہ نہیں.جمعہ اور
عید جب جمع ہو جائیں تو جمعہ کی بجائے ظہر کی نماز پڑھنے کی اجازت ہے مگر ہم تو وہی کریں گے جو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا.اگر کوئی جمعہ کی بجائے ظہر
پڑھنا چاہے تو اسے اجازت ہے مگر ہم تو جمعہ ہی پڑھیں گے.میں بھی یہی کہتا ہوں کہ جو شخص چاہے آج
جمعہ کی بجائے ظہر پڑھ لے مگر جو ظہر پڑھنا چاہتا ہے وہ مجھے کیوں مجبور کرتا ہے کہ میں بھی جمعہ نہ
پڑھوں.لیکں تو وہی کروں گا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا.کہ جمعہ ہی پڑھیں گے.ہمارا رب کیسا سخی ہے کہ اس نے ہمیں دو دو عیدیں دیں.یعنی جمعہ بھی آیا اور عیدالاضحی بھی آئی.اور اس طرح دو عیدیں خدا تعالیٰ نے ہمارے لئے جمع کر دیں.اب جس کو دو دو بچپڑی ہوئی چپاتیاں
میں وہ ایک کو رد کیوں کرے گا.وہ تو دونوں سے گا.سوائے اس کے کہ اسے کوئی خاص مجبوری پیش
آجائے اور اسی لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ اگر کوئی مجبور ہو کہ ظہر کی نماز پڑھ
لے جمعہ نہ پڑھے تو دوسرے کو نہیں چاہیے کہ اس پر طعن کرے اور اگر بعض لوگ ایسے ہوں جنہیں
دونوں نمازیں ادا کرنے کی توفیق ہو تو دوسرے کو نہیں چاہیے کہ ان پر اعتراض کرے اور کہے کہ انہوں
نے رخصت سے فائدہ نہ اٹھایا " سے
له : - الحنفية قالوا من ادرك الامام فى اى جزأ من صلاته نقد ادرك الجمعة ولو فى تشهد
مسجود السهو كتاب الفقه على المذاهب الاربعه م : له : " قال اجتمع عيدان في يومكم
هذا فمن شاء اجزاها من الجمعة وانا مجتمعون انشاء الله ابن ماجہ باب اذا اجتمع العبدان في يو
۳ - الفضل ۱۵ مارچ ۶۱۹۳۸ ، ۱۵ر فروری ۹۳۹له با
Page 183
144
اگر عید اور جمعہ اکٹھے ہو جائیں تو یہ جائز ہے کہ جمعہ کی بجائے ظہر کی نماز پڑھ لی جائے اور یہ
بھی جائز ہے کہ عید اور جمعہ دونوں پڑھ لئے جائیں کیونکہ ہماری شریعت نے ہر امر میں سہولت
کو مد نظر رکھا ہے.چونکہ عام نمازیں اپنے اپنے محلوں میں ہوتی ہیں لیکن جمعہ کی نمازہ میں سارے
شہر کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں.اسی طرح عید کی نمازہ میں بھی سب لئے گ اکٹھے ہوتے ہیں.اور ایک
دن میں دو ایسے اجتماع جن میں دُور دُور سے لوگ آکر شامل ہوں مشکلات پیدا کر سکتے ہیں.اس
لئے شریعت نے اجازت دی ہے کہ اگر لوگ برداشت نہ کر سکیں تو جمعہ کی بجائے ظہر پڑھ لیں.بہر حال اصل غرض شریعت کی یہ ہے کہ مسلمان اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ عرصہ کیلئے اکٹھے
بیٹھ سکیں کیونکہ اسلام صرف دل کی صفائی کے لئے نہیں آیا.اسلام قومی ترقی اور معاشرت کے
ارتقاء کے لئے بھی آیا ہے اور قوم اور معاشرت کا پتہ بغیر اجتماع میں شامل ہونے کے نہیں لگ
سکتا ہے.ایسا بھی جائز ہے کہ اگر جمعہ اور عید ایک روز جمع ہو جائیں تو عید کی نماز کے بعد نہ جمعہ پڑھا جائے
اور نہ ظہر بلکہ عصر کے وقت میں عصر کی نماز پڑھی جائے.چنانچہ عطاء بن ابی رباح کہتے ہیں کہ
ایک بار جمعہ اور عید الفطر دونوں ایک دن میں اکٹھے ہو گئے.حضرت عبداللہ بن نہ بریرہ نے فرمایا.ایک دن میں دو عیدیں جمع ہوگئی ہیں ان کو اکٹھا کر کے پڑھا جائے گا.چنانچہ آپ نے دونوں کے
لئے دو رکعتیں دوپہر سے پہلے پڑھیں.اس کے بعد عصر تک کوئی نماز نہ پڑھی.یعنی اس دن
صرف نماز عصر ادا کی.۲
حضرت خلیفہ المسیح الثالث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار اس روایت کے مطابق عمل کیا
اور عید کی نمازہ کے بعد عصر کی نمازہ ادا فرمائی.روایت کے الفاظ یہ ہیں :-
قال عطاء اجتمع يوم جمعة ويوم فطر على عهد ابن الزبير فقال
عیدان اجتمعا في يوم واحد فجمعهما جميعا فصلا هما ركعتين
بكرة لم يزد عليهما حتى صلى العصر
جمعہ کے بعد احتیاطی نماز
سوال :.بعض لوگ جمعہ کے بعد احتیاطی پڑھتے ہیں اس کے متعلق کیا حکم ہے ؟
جوا ہے :.قرآن شریف کے حکم سے جمعہ کی نماز سب مسلمانوں پر فرض ہے جب جمعہ کی نماز پڑھ لی تو حکم ہے کہ
-
۱۵۳
ه المصلح ٢٠ اكتوبر ١٩٤ له - ابو داؤد کتاب الصلوۃ باب اذا وافق يوم الجمعة ويوم العيد ما +
Page 184
14A
جاؤ اب اپنے کاروبار کرو.بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ انگریزوں کی سلطنت میں جمعہ کی نمازہ
اور خطبہ نہیں ہو سکتا کیونکہ بادشاہ مسلمان نہیں ہے.تعجب ہے کہ خود بڑے امن کے ساتھ
خطیہ اور نماز جمعہ پڑھتے بھی ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا.پھر کہتے ہیں کہ احتمال ہے
کہ جمعہ ہوا یا نہیں.اس واسطے ظہر کی نمازہ بھی پڑھتے ہیں اور اس کا نام احتیاطی رکھا ہے
ایسے لوگ ایک شک میں گرفتار ہیں ان کا جمعہ بھی شک میں گیا اور ظہر بھی شک میں گئی نہ یہ
حاصل ہوا نہ وہ - اصل بات یہ ہے کہ نماز جمعہ پڑھو اور احتیاطی کی کوئی ضرورت نہیں لیے
نماز عیدین
ماہ رمضان گزرنے پر یکم شوال کو افطار کرنے اور روزوں کی برکات حاصل کر نے کی توفیق پانے کی
خوشی میں عید الفطر اور دسویں ذوالحجہ کو حج کی برکات بیشتر آنے کی خوشی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی
قربانی کی یادمیں عید الاضحیہ منائی جاتی ہے.نماز عید کا اجتماع ایک رنگ میں مسلمانوں کی ثقافت اور
دینی عظمت کا مظہر ہوتا ہے اس لئے اس میں مرد عورت.بچے سبھی شامل ہوتے ہیں سیہ
عید کے دن کہنا کہ عمدہ لباس پہنا جائے خوشبو لگائی جائے.اچھا کھانا تیار کیا جائے.عید الفطر
ہو تو عید کی نماز کے لئے جانے سے پیشتر مساکین اور غرباء کے لئے فطرانہ ادا کیا جائے خود بھی کچھ کھا
پی کہ عید کی نمازہ کے لئے جائے لیکن اگر قربانیوں کی عید ہو تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد واپس آکر
کھانا زیادہ بہتر ہے ہی.اسی طرح عید کی نماز کے لئے آنے اور جانے کا راستہ مختلف ہو تو یہ منتخب
ہے اور زیادہ ثواب کا موجب ہے شیے
دونوں عیدوں پر عید کی دو رکعت نماز کسی کھلے میدان یا عید گاہ میں زوال سے پہلے پڑھی جاتی
ہے.حسب ضرورت عید کی نمازہ جامع مسجد میں بھی ادا کی جا سکتی ہے.عید کی نماز با جماعت ہی پڑھی جا سکتی ہے.اکیلے جائز نہیں.نماز عید کی پہلی رکعت میں ثناء
الحکم ار اگست شاه - فتادی مسیح موعود ص : ه: ترندی کتاب الصلواة باب خروج النساء في العيدين من :
: ابن ماجہ باب جا الاغتسال في العيدين ٩٣٥
ے :- ترمذی باب فی الا كل يوم الفطر قبل الخروج ابواب العيدين صلات:
ٹ:.ترمذی ابواب العیدین باب في خروج النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى العيد في طريق الخصات :
Page 185
149
کے بعد اور تعویذ سے پہلے امام سانت تکبیریں بلند آواز سے کہے اور مقتدی آہستہ آوازہ سے یہ تکبیرات
کہیں.امام اور مقتدی دونوں تکبیرات کہتے ہوئے ہاتھ کانوں تک اٹھائیں اور کھلے چھوڑ دیں لیے
رات کے بعد امام اعوذ اور بسم اللہ پڑھے.اس کے بعد سورۃ فاتحہ اور قرآن کریم کا کوئی حصہ بالجہر
پڑھ کر پہلی رکعت مکمل کرے.پھر دوسری رکعت کے لئے اٹھتے ہی پانچ تکبیریں پہلی تکبیرات کی طرح
ہے اور پھر یہ رکعت مکمل ہونے پر تشہد.درود شریف اور مسنون دعاؤں کے بعد سلام پھیر ہے.اس
کے بعد امام خطبہ پڑھے.جمعہ کی طرح عید کے بھی دو خطبے ہوتے ہیں.اگر عید کی نماز پہلے دن زوال
سے پہلے نہ پڑھی جا سکے تو عید الفطر دوسرے دن اور عید الاضحیہ تیسر سے دن تک زوال سے
پہلے پڑھی جاسکتی ہے کیے
دونوں عیدوں کی نماز ایک جیسی ہے فرق صرف یہ ہے کہ بڑی عید کی نماز ختم ہونے کے بعد
امام اور مقتدی کم از کم تین بار بلند آواز سے تکبیرات کہیں.اسی طرح نویں ذوالحجہ کی فجر سے تیرہویں کے
کی عصر تک با جماعت فرض نماز کے بعد بآواز بلند رہتی تکبیرات کہی جائیں.یہ تکبیرات مندرجہ ذیل ہیں:.الله اكبر - اللَّهُ أَكْبَرُ - لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ
وَلِلَّهِ الْحَمْدُ.یعنی اللہ سب سے بڑا ہے.اللہ سب سے بڑا ہے.اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں.اور اللہ سب سے بڑا ہے.اللہ سب سے بڑا ہے.اور اللہ تعالیٰ کے لئے ہی سب
تعریفیں ہیں.نے روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم كان يكبر في العيدين في الاولى
سبعا قبل القراءة وفي الآخرة خَمْسًا قبل القراءة
یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کی پہلی رکعت میں سات تکبیریں اور دوسری رکعت میں پانچ تکبیریں
کہا کرتے تھے.(ترندی منش ، ابن ماجه باب كم يكبر الامام فى صلاة العيدين صلا : -
: ابن ماجہ باب ماجاء في الخطبة في العيدين ما..ه : - ابو داؤد کتاب الصلاة باب اذالم يخرج الامام للعيد من يومه - المص
لله : - الف ، عن على أنه كان يكبر بعد صلاة الفجر يوم عرفة الى صلوة العصر من آخر ايام التشريق
ويكبر بعد العصر - رواه ابن ابي شيبة في مصنفه.واخرجه الحاكم في المستللك م۲۹۹ ، نصرالي ايه ۳۳
ب - أيام التشريق - هي العادى عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجه خانه شرح وقایه
۲۴۸
Page 186
١٨٠
نوٹے :.عید الاضحیہ کی نماز کے لئے آتے ہوئے اور واپس جاتے ہوئے بھی یہ تکبیرات
بلند آواز سے کہنا مسنون ہے لیے
نماز عید
سوال : کیا عید کی نماز ضروری ہے ؟
جوانے :.عید کی نمازہ سنت مؤکدہ ہے.چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عید کے لئے
عام لوگوں کے علاوہ عورتیں اور بچے بھی آئیں.البتہ حائضہ عورتیں نماز میں شامل نہ ہوں وہ الگ
بیٹھ کر تکبیر و تحمید میں مشغول رہیں.عید کی نماز با جماعت ہی ہو سکتی ہے.یہ اکیلئے جائز نہیں.تکبیر تحریمہ کے بعد ثناء پڑھ کر پہلی
رکعت میں سات تکبیریں کہی جائیں.امام بلند آواز سے یہ تکبیریں کہے اور مقتدی آہستہ آہستہ
ہر تکبیر کے ساتھ ہاتھ کانوں تک بلند کر کے سیدھے چھوڑ دیئے جائیں باندھے نہ جائیں جب
امام قرأت شروع کر لے تو پھر ہاتھ باندھ لئے جائیں.دوسری رکعت میں قرأت سے پہلے اسی
طرح پانچ تکبیریں کہی جائیں.اگر امام یہ تکبیریں نہ کہے اور بھول جائے تو اس غلطی کے تدارک
کے لئے سجدہ سہو کرنا ضروری ہوگا.عید کی نماز کا وقت صبح اندازہ آنیزه برابر سورج نکل آنے
کے بعد شروع ہوتا ہے اور دوپہر یعنی زوال سے قبل تک رہتا ہے.تاہم جلد نماز پڑھنا زیادہ
ثواب کا موجب ہے.سوال : تکبیرات عیدین کتنی ہیں.جماعتی مسلک کیا ہے ؟
جواب : جماعت احمدیہ کا مسلک جو تواتر علی کی حیثیت رکھتا ہے.یہی ہے کہ پہلی رکعت میں سات
تکبیریں اور دوسری رکعت میں پانچ تکبیریں قرائت سے پہلے کہی جادیں.ہر تکبیر کے ساتھ ہاتھ
کانوں تک اُٹھائے جائیں اور پھر کھلے چھوڑ دیئے جائیں.ساتویں یا پانچویں تکبیر کے بعد سینہ
پر ہا تھ باندھے جائیں اس کے بعد تعوذ اور علیم اللہ کے ساتھ قرأۃ شروع کی جائے.اس بارہ میں صحابہ کرام کا عمل اور ان کے اقوال سند کی حیثیت رکھتے ہیں.حضرت
ابو ہریرہ اور عبد اللہ بن عمریضہ کا طریق عمل یہ تھا کہ پہلی رکعت میں سات تکبیریں اور دوسری
رکعت میں پانچ تکبیریں قرائت سے پہلے کہا کرتے تھے.حضرت عبداللہ بن مسعود پہلی رکعت میں تین تکبیریں قرأة سے پہلے اور دوسری رکعت میں
: عن ابن عمر انه كان اذعد اليوم الفطر ويوم الاضحى يجهر بالتكبير حتى يأتى المصلى و دار قطني منشا ،
1
بیهقی :
Page 187
تین تکبیریں قرآہ کے بعد اور رکوع سے پہلے کہتے تھے.اس سلسلہ میں یہ امر مد نظر رکھنا چاہیے کہ صحابہ کرام کے اس قسم کے عمل کے متعلق اصول
یہ ہے کہ صحابہ کے یہ اعمال ان کی ذاتی رائے کی بناء پر نہیں بلکہ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کے کسی عمل یا حضور کے کسی ارشاد سے یہ امر اخذ کیا ہے.بہر حال جماعت احمدیہ کا مسلک حضرت
ابو ہریرہ کی روایت کے مطابق ہے.لیکن اس کے باوجود اگر کسی احمدی نے دوسری رکعت میں سہوگا
یا کسی اور وجہ سے قرأۃ کے بعد تکبیریں کہی ہیں تو یہ کہنا درست نہ ہوگا کہ اس کا عمل اسلامی روایات
کے خلاف اور نا جائزہ ہے.البتہ اس طریق کو دستور العمل نہیں بنانا چاہیے کیونکہ ایسا کہ نا عبادات
میں جماعت کی عملی یکجہتی کے خلاف ہے.سوال: نماز عید کی تکبیروں کا ثبوت کیا ہے ؟
جو ا ہے : کسی مسئلہ کا ثبوت دو طرح سے ہوتا ہے یا تو قرآن کریم میں اس کا ذکر ہو یا حدیث سول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی وضاحت کی گئی ہو.چنانچہ عیدین کی تکبیرات
کی تعداد کا ثبوت قرآن کریم
سے اجمالاً اور حدیث رسول سے تفصیلاً ہمیں ملتا ہے.ترندی و ابن ماجہ کی روایت ہے کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں سات اور دوسری رکعت میں پانچ تکبیریں قرأت سے پہلے کہا
کرتے تھے.حدیث کے الفاظ یہ ہیں :-
إن النبى صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ فِي الْعِيدَيْنِ فِي الْأَوَّلِ سَبْعًا
قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَفِي الآخِرَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَأَة - له
سوال :.عید کی نماز کے بعد امام ایک خطبہ پڑھے یا جمعہ کی طرح دو خطبے.خطبہ کے بعد دعا کے بارہ
میں کیا حکم ہے ؟
جوا ہے.عیدین میں بھی اسی طرح دار خطبے پڑھنے چاہئیں جس طرح جمعہ میں دو خطبے ہوتے ہیں.حدیث سے ایسا ہی ثابت ہ ہے.ایک اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں :-
ه ترندی کتاب الصلواة باب التكبير في العيدين من جلد اول ، ابن ماجہ باب ما جاء في كم يک بر الامام في
مه له :- عن جابر قال خرج رسول اللہ صلی الله عليه وسلم يوم فطر
صلوة العيدين صك
او اضحى فخطب قائما ثم قعد قعدة ثم قام و ابن ماجہ باب في الخطبة في العيدين من :
Page 188
١٨٣
عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ السُّنَّةُ مَنْ يَخْطُبَ الإِمَامُ فِي الْعِيْدَيْنِ
لبَتَيْنِ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِجَلوم - رواه الشافعي - ام
دوسرے خطبہ کے بعد ہاتھ اُٹھا کر دکھا کہ نا ضروری نہیں.یعنی یہ جز و خطبہ نہیں تاہم اگر
کوئی اس طرح ہاتھ اُٹھا کر دعا مانگے تو یہ جائز ہے اور مرکز میں اس کے مطابق عمل ہے.لیکن
اس کا التزام حدیث اور سنت سے ثابت نہیں اس لئے دوسرے خطبہ کے بعد اگر کسی جگہ ہاتھ
اُٹھا کر دعانہ مانگی جائے تو اس پر اعتراض نہیں کرنا چاہیئے.قربانی کے مسائل
قربانی صاحب استطاعت کے لئے سنت کے مؤکدہ اور واجب ہے اور اس میں ایک حکمت یہ ہے کہ قربانی
دینے والا اشارہ کی زبان میں اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ جس طرح یہ جانور جو مجھ سے اونی ہے میرے لئے
قربان ہو رہا ہے.اسی طرح اگر مجھ سے اعلیٰ چیزوں کے لئے میری جان کی قربانی کی ضرورت پڑے گی تو ہیں
اُسے بخوشی قربان کر دوں گا.غرض قربانی ایک تصویری زبان ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جانور ذبح کرنے
والا اپنے نفس کی قربانی پیش کرنے کے لئے تیار ہے.قربانی کے لئے اُونٹ، گائے، بکری، بھیڑ، دنبہ.ان میں سے کوئی سا جانور ذبح کیا جاسکتا ہے اونٹ
اور گائے سات آدمیوں کی طرف سے اور بھیڑ بکری وغیرہ ایک آدمی کی طرف سے کافی ہے اور انسان قربانی
کی نیت میں اپنے کنبہ کو بھی شامل کر سکتا ہے سیکے
اونٹ تین سال ، گائے دو سال اور بھیڑ بکری وغیرہ ایک سال کی کم از کم ہونی چاہئیے.ڈنبر اگر
موٹا تازہ ہو تو چھ ماہ کا بھی جائز ہے.قربانی کا جانور کمزور اور عیب دار نہیں ہونا چاہیئے.لنگڑا.کان کٹا.سینگ ٹوٹا اور کانا جانور جائز نہیں.اسی طرح بیمار اور لاغر کی قربانی بھی درست نہیں لیکے
ے نیل الاوطار باب خطبته الحيد واحكامها هي :
#
له : - عن ابن سیرین قال سألت ابن عمر عن الضحايا أواجبة هى قال ضحى رسول الله صلى الله عليه
وسلم والمسلمي من بعده وجرت به السنة وابن ماجه ص ۲۳) سد : ترندی ابواب الاضاحی
باب في الاشتراك في الاضحيه ملا ، ابن ماجه ۳۲۵ باب من ضحى بشأة عن اهله به که :- جامع ترمذی باب مالا يجوز
من الاضاحي :
Page 189
۱۸۳
قربانی کا وقت دس ذی الحجہ کو عید کی نماز کے بعد سے لے کر بارہ ذی الحجہ کو سورج کے نؤدب ہونے سے
پہلے تک رہتا ہے.قربانی کا گوشت صدقہ نہیں.انسان خود بھی کھا سکتا ہے اور دوستوں کو بھی کھلا سکتا
ہے.غریبوں کو بھی اس میں سے کھلانا چاہئیے.بہتر ہے کہ تین حصے کہ ہے.ایک حصہ خود رکھے ، ایک رشتہ داروں
میں تقسیم کرتے اور ایک اللہ غریبوں میں ہیم.عقیقہ
بچہ کی پیدائش پر ساتویں روز سر کے بال اتروانا اور ان بالوں کے برابر چاندی یا سونا بطور صدقہ دینا
نام رکھنا اور عقیقہ کرنا مسنون ہی ہے.حدیث میں اس کی فضیلت بیان ہوئی ہے.عقیقہ سے مراد جانور کا
ذبح کرنا ہے." لڑکے کی صورت میں دو بکرے یا دنبے اور لڑکی کی صورت میں ایک بکرا یا دنبہ وغیرہ ذبیح
کرنا چاہیئے.جانور اچھی عمر کا موٹا تازہ ہو گو اس کے لئے عمر کی وہ شرط لازمی نہیں جو قربانی کے جانور کیلئے ہے.عقیقہ کا گوشت انسان خود بھی کھا سکتا ہے اور دوسرے دوست احباب اور رشتہ داروں کو
بھی دے سکتا ہے.پکا کر دعوت بھی کر سکتا ہے.غریبوں کو بھی اس میں سے حصہ دینا چاہیئے.اگر
بامر مجبوری دو جانور ذبح نہ کر سکے تو ایک پر بھی کفایت کر سکتا ہے.نمازیں جمع کرنا
بیماری بسفر بارش طوفان با دو باراں سخت کیچڑ سخت اندھیرے میں جبکہ مسجد میں بار بار آنے
جانے کی دقت کا سامنا ہو.اسی طرح کسی اہم دینی اجتماعی کام کی صورت میں ظہر و عصر مغرب اور عشاء کی
نماندوں
کو جمع کیا جا سکتا ہے.جماعت سے بھی اور اکیلے بھی.جمع تقدیم یعنی ظہر کے وقت میں ظہر اور عصر
اور جمع تاخیر یعنی عصر کے وقت میں ظہر اور عصر دونوں صورتیں جائز ہیں.اسی طرح مغرب کے وقت میں
مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھی پڑھنا جمع تقدیم ہے اور عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء کی نمازیں اکھٹی
پڑھنا جمع تاخیر ہے لیکہ نمازیں جمع کرنی ہوں تو ایک آذان کافی ہے البتہ اقامت ہر ایک نمازہ کے لئے
الگ الگ ہوگی.:- تمندی باب كراهية اكل الاضحية فوق ثلثة ايام سه : - ابن ماجه باب الحقیقہ م ؟
ه: ابن ماجہ باب الحقيقه مث :
- تریدی باب في المتطوع في السفر :
Page 190
۱۸۴
با جماعت نمازیں جمع کرنے کی صورت میں اگر امام پہلی نما نہ پڑھانے کے بعد دوسری نماز پڑھا رہا
ہو تو و شخص بعد میں مسجد میں آئے اگر اسے معلوم ہو جائے کہ امام کونسی نمانہ پڑھا رہا ہے تو پھر وہ پہلے اس
نمازہ کو ادا کرہ سے جو امام پڑھا چکا ہے.اس کے بعد امام کے ساتھ شامل ہو لیکن اگر اسے معلوم نہیں ہوسکا
کہ کونسی نماز ہو رہی ہے اور وہ یہ سمجھ کر شامل ہو جاتا ہے کہ امام کی یہ پہلی نماز ہے تو امام کی نیست
کے مطابق اس کی نمازہ ہو جائے گی اور پھر بعد میں وہ پہلی نماز پڑھ لے.بہر حال علم ہو جا نیکی صورت
میں نمازوں کی ترتیب کو قائم رکھنا ضروری ہے خواہ جماعت ملے یا نہ ملے.اے
سوال : اگر کسی شخص کی نماز ظہر یا عصر رہ گئی ہو اور امام مغرب کی نماز پڑھا رہا ہو تو اس کو کونسی نماز
پڑھنی چاہیے.جماعتی مسلک کیا ہے.جواب : صورت مذکور کے مطابق بعد میں آنے والے کو اگر یاد ہے کہ اس کی ظہر یا عصر کی نما نہ رہ گئی ہے یا
نمازہ جمع کی صورت میں اُسے علم ہے کہ امام فلاں نماز پڑھا رہا ہے تو اُسے چاہیے کہ پہلے وہ نماز پڑھے
جو اس کی رہ گئی ہے کیونکہ اصولاً نمازوں میں ترتیب کو قائم رکھنا ضروری ہے.خواہ اس صورت
میں وہ نماز با جماعت میں شامل نہ ہو سکے.البتہ اگر اُسے یاد نہیں کہ اس کی ظہر یا عصر کی نماز رہ گئی
ہے یا علم نہیں کہ کونسی نماز ہو رہی ہے اور وہ شامل ہو جاتا ہے تو جو نماز امام کی ہے وہی اس کی
ہو جائے گی اور رہی ہوئی نماز وہ بعد میں پڑھ لے کیونکہ بھول اور سہو معاف ہے.حضرت خلیفہ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں :-
میں نے خود حضرت مسیح موعود علیہ السّلام سے سنا ہے کہ اگر امام عصر کی نمائنہ پڑھ
رہا ہو اور ایک شخص مسجد میں آئے جنسی ابھی ظہر کی نمازہ پڑھتی ہو.یا عشاء کی نماز ہو
رہی ہو اور ایک شخص مسجد میں آجائے جنسی ابھی مغرب
کی نماز پڑھنی ہو اسے چاہیئے کہ
وہ پہلے ظہر کی نماز علیحدہ پڑھے اور پھر امام کے ساتھ شامل ہو یا مغرب کی نمازہ پہلے
علیحدہ پڑھے اور پھر امام کے ساتھ شامل ہو.جمع بین الصلوامین کی صورت میں بھی
اگر کوئی شخص بعد میں مسجد میں آتا ہے جبکہ نمازہ ہو رہی ہو تو اس کے متعلق بھی حضرت
مسیح موعود علیہ السلام کا یہی فتویٰ ہے کہ اگر اُسے پتہ لگ جاتا ہے کہ امام عصر کی نمازہ
پڑھ رہا ہے تو اُسے چاہیے کہ وہ پہلے ظہر کی نماز علیحدہ پڑھے اور پھر امام کے ساتھ
شامل ہو.اسی طرح اگر اُسے پتہ لگ جاتا ہے کہ امام عشاء کی نما نہ پڑھ رہا ہے تو وہ
پہلے مغرب کی نمازہ علیحدہ پڑھے اور پھر امام کے ساتھ شامل ہو.لیکن اگر اسے معلوم نہ
له الفضل ارجون له الفضل ستمبر ناله با
،
Page 191
۱۸۵
ہو سکے کہ کونسی نماز پڑھی جا رہی ہے اور وہ جماعت کے ساتھ شامل ہو جائے.ایسی
صورت میں جو امام کی نماز ہوگی وہی نماز اس کی ہو جائے گی بعد میں وہ اپنی پہلی
نماز پڑھ لے.مثلاً اگر عشاء کی نمازہ ہو رہی ہو اور ایک ایسا شخص مسجد میں آجاتا ہے
جنسی ابھی مغرب کی نماز پڑھنی ہے تو اگر اُسے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ عشاء کی نماز
ہے تو وہ مغرب کی نماز پہلے علیحدہ پڑھے اور پھر امام کے ساتھ شامل ہو.لیکن
اگرا سے معلوم نہ ہو سکے کہ یہ کونسی نماز ہو رہی ہے تو وہ نام کے تھے شامل ہو جائے
اس صورت میں اس کی عشاء کی نماز ہو جائے گی.مغرب کی نماز وہ بعد میں پڑھ
ہے.یہی صورت عصر کے متعلق ہے یہ لے
نمازوں کا جمع کرنا
حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ۳ دسمبر نشہ میں تقریر کرتے ہوئے فرمایا : -
" دیکھو ہم بھی رخصتوں پر عمل کرتے ہیں نمازوں کو جمع کرتے ہوئے کوئی دو ماہ سے
زیادہ ہو گئے ہیں بسیب بیماری کے اور تفسیر سورۃ فاتحہ کے لکھنے میں بہت مصروفیت کے
سبب ایسا ہورہا ہے اور ان نمازوں کے جمع کرنے میں تُجمَع لَهُ الصَّلوة کی حدیث
بھی پوری ہو رہی ہے کہ مسیح موعود کی خاطر نمازیں جمع کی جائیں گی.اس حدیث سے یہ
بھی ثابت ہوتا ہے کہ مسیح موعود نمانہ کے وقت پیش امام نہ ہو گا بلکہ کوئی اور ہو گا اور وہ
پیش امام سیح کی خاطر نما نہیں جمع کرائے گا " سے
سوال : - کن حالات میں نمازہ جمع ہو سکتی ہے ؟
جواب : سخت خطرہ ہو.سفر ہو.بارش ہو.بیماری ہو سخت سردی ہو.کیچڑ اور سخت اندھیرا ہو
کوئی اہم دینی اجتماع ہو یا اسی قسم کی کوئی اور اہم دینی مصروفیت ہو.جس کی وجہ سے نمازیوں کو
دوبارہ جمع ہونے میں خاص تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہو.یہ فیصلہ کرنا کہ آیا ان حالات میں سے کوئی حالت ایسی ہے کہ نمازیں جمع کر لی جائیں دراصل
امام اور مقتدیوں کی رائے پر منحصر ہے.اگر مقتدیوں کی اکثریت صورت حال کے اس اقتضاء کو
مانتی ہو تو امام کو ان کی رائے کا احترام کرنا چاہیے.اسی طرح اگر امام کی رائے ہو اور وہ نماز شروع
کر دے تو مقتدیوں کو اس کی اقتداء کرنی چاہیئے.له الفضل ۲۷ جون له : ۱۹ - مسند احمد ص : ه: - فتاوی مسیح موعود ما ؟
Page 192
174
بہر حال جب نمازیں جمع کرنے کا فیصلہ ہو جائے تو پھر سب مقتدیوں کو اس کی پابندی کرنی
چاہیے.کسی فرد واحد کے لئے یہ جائزہ نہیں کہ وہ عملی اختلاف کر سے اور ساتھ نمانہ نہ پڑھے ہاں تومی
اور دلیل کے ساتھ اپنی رائے کا اظہار کر سکتا ہے کہ اس کے نزدیک یہ فیصلہ درست نہیں.بہرحال
یہ فیصلہ کرنا کہ آیا حالت ایسی ہے کہ نماز جمع کی جا سے یا نہ کی جائے اس کا تعلق دراصل انہی لوگوں
سے ہے جن کو اس صورت حال سے واسطہ پڑا ہے.ان کی رائے ہی فیصلہ کن ہوگی.سوال:.نماز کے وقت سخت گہرے بادل ہوں اور بارش ہونے کا کافی امکان ہو تو کیا ظہر اور عصریا
مغرب اور عشاء کی نمازیں جمع کی جاسکتی ہیں ؟
جواب : جمع نماز کی اصل بنیاد حرج سے بچنا ہے.اگر امام الصلوۃ اور اس کے ساتھ نمازیوں کی اکثریت
کی یہی رائے ہو کہ آسمان کی حالت کے پیش نظر نمازیں جمع کر لینی چاہئیں تو ایسا کہ نا جائز ہے غرض
اس بارہ میں مناسب فیصلہ موجود لوگوں کی اکثریت مشمول امام کر سکتی ہے.اور جب یہ فیصلہ
ہو جائے تو پھر کسی فرد واحد کے لئے یہ جائزہ نہیں کہ وہ نماز میں تخلف کہ سے.خواہ اس کی رائے
میں یہ فیصلہ غلط ہی کیوں نہ ہو.والے :.کیا سردی کی وجہ سے نماز جمع ہو سکتی ہے جبکہ کوئی بارش نہ ہو رہی ہو اور نہ ہی بارش کے آثار ہوں ؟
جوا ہے :.حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علی وسلم نے مدینہ میں بارش اور مرض کے بغیر نمازی جمع کرائیں.حضرت ابن عباس جو اس حدیث کے راوی ہیں اُن سے پوچھا گیا کہ آخر اس کی وجہ کیا تھی تو آپ نے
جواب دیا.مقصد یہ تھا کہ لوگ حرج سے بچ جائیں اس حدیث میں اس طرف اشارہ ہے کہ بارش
اور مرض کے علاوہ بھی بعض اور مشکلات یا دینی مصروفیات نمازہ جمع کرنے کا موجب بن سکتی ہیں اسی
پر ہم شدید سردی کو بھی قیاس کر سکتے ہیں لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس بہانے سے لوگوں میں نماز
جمع کرنے کی عام عادت جڑ نہ پکڑ سکے اور ضرورت کو ضرورت اور مجبوری پر ہی محمول سمجھا جائے.سوال : جلسہ سالانہ پر نمازیں جمع کیوں کی جاتی ہیں ؟
جواب: - حدیث شریف میں اس قسم کے مواقع پر نمازہ جمع کرنے کی اجازت موجود ہے.حج کے موقع پر اور
سفر کے دوران نمازہ جمع کرنے کی اجازت متعدد حدیثوں سے ثابت ہے بلکہ بعض اوقات خود مدینہ میں
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں جمع کر کے پڑھائیں.چنانچہ مندرجہ ذیل روایت قابل غور ہے :-
عَنِ ابْنِ عَبَاس اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِالْمَدِينَةِ سَبْعًا وَ ثَمَانِيًا
صَلَّى
الظهْرَ وَ الْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءُ - ٢- جَمْعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ
وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ مِنْ غَيْرِ خَوْنٍ
مسلم باب الجمع بين الصلواتين في الحضر ص :
Page 193
1 AL
وَلَا مطرٍ - يَيْلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا أَرَادَ بِذَلِكَ قَالَ أَرَادَ أَنْ لا يُعيج
سوال :.ایک شخص کی ڈیوٹی ارد گرد کے مقامات پر دورہ کرنے کی لگی ہوئی ہے جو کہ تو سیل سے زیادہ ہے
اسی طرح سے اکثر نمازیں بھی جمع کرنی پڑتی ہیں.نیز باہر رہتے ہوئے وہ جمعہ بھی نہیں پڑھ سکتا.اگر
نما نہ جمعہ ادا کرنے کی غرض سے ڈیوٹی سے غیر حاضر ہو جائے تو کیا اس میں شرکا کوئی حرج تو نہیں.نیز
اگر سائیکل پر ہی نماز ادا کر لی جائے تو اس میں شرکا کوئی حرج ہے ؟
جواب : نماز اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کی گئی ہے اور اسے وقت پر پڑھنا چاہیے.اگر کوئی مجبوری ہے
مثلاً بیمار ہے یا مسافر ہے یا ایسی ڈیوٹی پر ہے کہ افسر نماز کے اوقات میں چھٹی نہیں دیتا تو پھر
نمازہیں جمع بھی کی جاسکتی ہیں.نیز ایسے حالات میں تاخیر سے بھی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں.جمعہ مسافر پر فرض نہیں البتہ اگر
اسے موقع مل جائے اور اس کے سفر یا کام میں حرج نہ ہوتا ہو تو جمعہ پڑھے اس میں بہر حال
برکت ہے.سائیکل پر بغیر اثر مجبوری کے املا جان کا خطرہ ہو یا غیر معمولی جلدی ہو اور وقت جارہا ہوں
نماز پڑھنا جائزہ نہیں.اصل چیز اللہ تعالیٰ کا خوف اور تقویٰ ہے اس کے ماتحت انسان اللہ تعالیٰ
کی عبادت بھی کر سے اور اپنے دنیوی فرائض کو بھی ادا کرہ ہے.ملازمت کے فرائض کو ادا کر نابھی اسلام
کے احکام میں شامل ہے.سوال: نمازیں جمع کرنے کی صورت میں سنتیں پڑھنی چاہئیں یا نہیں ؟
ہوا ہے: حضرت مسیح موعود علیہ السّلام کے عمل سے ہم نے جو کچھ تواتر سے دیکھا اور پوچھنے والوں کے جواب میں
آپ نے ہمیشہ جو کچھ فرمایا ہے وہ یہی ہے کہ نمازیں جمع کر نے کی صورت میں فرضوں سے پہلی سنتیں بھی
اور بعد کی سنتیں بھی معاف ہو جاتی ہیں.سوال : اگر نماز جمعہ کے ساتھ عصر کی نمازہ جمع کی جائے تو کیا پھر بھی سنتیں معاف ہیں ؟
جواب :.نماز جمعہ سے قبل جو سنتیں پڑھی جاتی ہیں وہ دراصل جمعہ کے نقل ہیں اور جمعہ کے ساتھ مخصوص
ہیں.اس لئے نماز جمعہ سے قبل سنتیں بہر حال پڑھنی چاہئیں لیے
ه
(ب) مغرب اور عشاء کی نمازیں جمع کرنے کی صورت میں صرف وتر پڑھنے چاہئیں باقی سنتیں معاف
ہیں.ہاں اگر کوئی پڑھ سے تو گناہ بھی نہیں کیونکہ یہ نفل ہی تو ہیں لیکن ظہر اور عصر کو جمع کرنے کی صورت
اسلم باب الجمع بين الصلاتين في الحضر ص : ١٥٣ الفضل ۲۴ جنوری ۱۳ ، ۱۴ اکتوبر شاه :
Page 194
میں بعد میں سنن اور نوافل نہیں پڑھنے چاہئیں کیونکہ عصر کے بعد نواخلی نا جائز ہیں.خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق عمل کیا تھا یا آپ نے کیا فرمایا ہے.اس بارہ میں یہ امر واضح
ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں جمع کرنے کی صورت میں سنتیں نہیں پڑھا کرتے تھے.اسی طرح آپ
کا کوئی فرمان بھی نہیں کہ اس صورت میں سنتیں ضرور پڑھی جائیں.اس بارہ میں بخاری کی یہ روایت
واضح ہے :-
جَمَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعِ
كُل وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِاقَامَةٍ وَلَمْ يُسَبِّحُ بَيْنَهُمَا وَلَا عَلَى أَثَرِ كُل
واحدة منهما.له
یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے ایام میں مزدلفہ کے مقام پر مغرب اور عشاء کی نمازیں
جمع کیں.ہر ایک کے لئے علیحدہ علیحدہ اقامت کہی گئی.آپ نے سنتیں نہ درمیان میں پڑھیں اور
نہ بعد س - لہ ، سے
سوال :.سفر میں صبح کی دو سنتیں کیوں معاف نہیں ہیں جبکہ دوسری نمازوں کی سنتیں معاف ہیں ؟
جواب :.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں صبح کی سنتیں پڑھی ہیں.اس لئے اقمت بھی پڑھتی ہے
متعلقہ حدیثیں درج ذیل ہیں :-
4>
(۲)
رَكَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّفَرِ رَكَعَنِي الْفَجْرِ له
رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں فجر کی دو رکعت سنت نماز ادا کی.فجر
كَانَتْ عَائِشَة تَقُولُ لَمْ يَدَعِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ
قبل الفَجْرِ صَحِيحا وَلَا مَرِيضًا فِي سَفَرٍ وَلَا حَضَرِ
حضرت عائشہ نہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہ آپ تندرست ہوتے
یا بمیار - سفر میں ہوتے یا مقیم صبح کی دو رکعت سنت نماز پڑھنا کبھی ترک نہیں کیا.در نه عام دستور آپ کا یہ تھا کہ باقی نمازوں میں آپ بحالت سفر سنتیں نہیں پڑھتے تھے.چنانچہ
ه : بخاری کتاب الحج باب من جمع بينهما ولم يتطوع : : ترندی البواب الصلوة السفر ص :
:
: - ابو داؤد كتاب الصلوة باب التطوع في السفر ص : ٢: بخارى كتاب الصلوة باب من تطوع في السحر
ہے : کشف الغمہ ص ہے
:
-:
Page 195
روایت ہے :
-:
نماز سفر
عَنِ ابْنِ عُمَرَ انَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَتَطَوَّعُ فِي السَّفَرِ
قَبْلَ الصَّلوة ولا بعدها.حضرت ابن عمر نہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں فرضوں سے پہلے اور
بعد کوئی سنت نمازہ نہیں پڑھتے تھے.شروع میں ظہر و عصر اور عشاء کی نمازہیں فجر کی طرح دو دو رکعت تھیں لیکن بعد میں سفر کی حالت
میں تو یہ دو دو رکعت ہی رہیں لیکن اقامت کی حالت میں دوگنی یعنی چار چار رکعت کر دی گئیں اس تبدیلی
کی بناء پر مسافر جس کا کسی جگہ پندرہ دن سے کم شہر نے کا ارادہ ہو ظہر عصر اور عشاء کی نماز دو دو رکعت
پڑھے گا اور مقیم چار چار رکعت پڑھے گا.مغرب اور فجر کی رکعتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی.حضرت عائشہ فرماتی ہیں :-
فرضت الصلوة ركعتين فى الحضر والسفر فاقرت صلواة السفر
وزيد في صلوة الحضرية
اگر انسان کسی ایسے عزیز کے گھر میں مقیم ہو جسے وہ اپنا ہی گھر سمجھتا ہے.جیسے والدین کا گھر.سسرال کا گھر یا مذہبی مرکز مثلاً مکہ مدینہ.قادیان - ربوہ وغیرہ تو پندرہ دن سے کم قیام کے دوران
میں چاہے تو اس رخصت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دو رکعت پڑھے اور چاہے تو پوری نماز یعنی
چار رکعت پڑھے.سفر میں وتمر اور فجر کی دو سنتوں کے علاوہ باقی سنتیں معاف ہو جاتی ہیں.نقل پڑھے یا نہ
پڑھے.یہ انسان کی اپنی مرضی پر منحصر ہے.سفر میں نمازیں جمع کرنا بھی جائز ہے.اگر امام مقیم ہو تو مسافر مقتدی اس کی اتباع میں پوری نمازہ پڑھے گا.اور اگر امام مسافر ہو
:- ترمذی کتاب الصلوۃ باب ما جاء في التطوع في المسفرصت :
-
کتاب الاثار باب الصلوة في السفر ص: - ترمذی کتاب الصلوۃ باب كم نقصر الصلواة صب :
179
۱۳ - ابو داؤد باب صلاة المسافر من :
Page 196
14.تو امام دو رکعت پڑھے گا اور اس کے تعظیم مقندی کھڑے ہو کر بقیہ رکھتیں پوری کر کے سلام پھیریں گے ہے.ان بقیہ دو رکعتوں میں وہ صرف سورۃ فاتحہ پڑھیں گے.سفر اور قصر
سوال : قصر کا مسئلہ کیا ہے.نمازہ کب قصر کی جاتی ہے ؟
جواب : - جماعت احمدیہ کے مسلک کے مطابق مسافر کے لئے نماز قصر کرنے کے معنے یہ ہیں کہ وہ چار
رکعت فرض نماز کی بجائے دو رکعت نماز پڑھے.سفر کسے کہتے ہیں اور اس کی مقدار کتنی ہو اس کے بارہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ارشاد
ایک تو سفر ہوتا ہے اور ایک سیر ہوتی ہے.سفر کی نیت سے اگر تین کو میں جانا ہو
جیسے لدھیانہ سے پھلور تو نماز قصر کرنی چاہیے.یہی صحابہ کہ آم کا معمول تھا اور بعض
ضعیف پیر فرتوت اور حاطہ عورتیں ہیں ان کے لئے تو کوس بھر ہی سفر ہو جاتا ہے
ہاں سیر کے لئے چاہے آٹھ کوس چلا جائے.نماز قصر نہیں ہے؟ ۲
ایک اور موقع پر سوال ہوا کہ اگر کوئی تین کو کسی سفر پر جائے تو کیا نمازوں کو قصر کہ ہے ؟ تو حضور
نے فرمایا :-
ہاں مگر دیکھو اپنی نیت کو خوب دیکھ لو.ایسی تمام باتوں میں تقویٰ کا بہت خیال رکھنا
چاہیے.اگر کوئی ہر روز معمولی کا روبار یا سفر کے لئے جاتا ہے تو وہ سفر نہیں بلکہ سفر
وہ ہے جسے انسان خصوصیت سے اختیار کرے اور صرف اس کام کے لئے گھر
چھوڑ کر جائے اور عرف میں وہ سفر کہلاتا ہے " سے
لها عن عمران بن حصين قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدت معه الفتح فاقام
بمكة ثماني عشرة ليلة لا يصلى الأركعتين ويقول يا اهل البلد صلوا اربعا فانا قوم سفر
ابو داؤد كتاب الصلوة باب متى يتم المسافرص
ان عمر بن الخطاب كان اذا قدم مكة صلى بهم ركعتين ثم يقول يا اهل مكة المواصلوتكم فانا
قدم سفر (موطا مالک : نه تذکرۃ المہدی ملا فتادی احمدیه هنا : ۳ - فتاوی مسیح موعود ص :
Page 197
۱۹۱
ب - " عرض کیا گیا حضور بالہ جاتے ہیں تو قصر فرماتے ہیں.فرمایا.ہاں کیونکہ وہ سفر ہے.ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی طبیب یا حاکم بطور دورہ کئی گاؤں پھرتا رہے تو وہ اپنے
تمام سفر کو جمع کر کے اُسے سفر نہیں کہہ سکتا ہے
ج "جو شخص رات دن دورہ پر رہتا ہے اور اس بات کا ملازم ہے وہ حالت دورہ
میں مسافر نہیں کہلا سکتا.اس کو پوری نمانہ پڑھنی چاہیئے " ہے
۳ - سفر کے دوران کسی ایک جگہ قیام کتنے دنوں کا ہو تو انسان کو مقیم سمجھا جائے اور اسے پوری نماز
پڑھنی چاہئیے ؟
الف : - حنفیوں کے نزدیک چودہ دن تک قیام کی نیت حالت سفر کو ختم نہیں کرتی البتہ اگر کسی قابل
رہائش جگہ میں پندرہ یا دستی زیادہ دن قیام کی نیت ہو تو اقامت
کا حکم ثابت ہو گا اور
نمازہ پوری پڑھنی پڑے گی.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں بیس دن تشریف فرما ر ہے لیکن آپ نے نماز قصر
فرمائی کیونکہ جہاں آپ مقیم تھے وہ کوئی آبادی نہ تھی بلکہ ویران علاقہ تھا.تے
ب - حضرت امام مالک اور حضرت امام شافعی کا مسلک یہ ہے کہ اگر کہیں چار دن قیام کرنا ہو
تو نماز پوری پڑھی جائے گی گویا تین دن قیام کی صورت میں نمانہ قصر کی جاسکتی ہے.حضرت خلیفہ البیع الاول کا ارشاد ہے.چار دن
کا ارادہ اقامت ہو تو مسافر مقیم ہو جاتا
ہے.سے
موطا امام مالک میں ہے.من اجمع اقامة اربع ليال وهو مسافر اتم الصلوة فيه
ج.صحیح رائے یہ ہے کہ تین دن قیام کی نیت ہو تو نماز قصر کرنی چاہیئے کیونکہ یہ متفق علیہ
مدت مسافرت ہے.اس سے زیادہ چودہ دن تک قیام کی صورت میں اختیار ہے.چاہے کوئی قصر کرے چاہے پوری پڑھے گو قصر زیادہ پسندیدہ ہے.حضرت خلیفہ اسیح الثانی نے ایک سوال کے جواب میں فرمایا :-
البدر ۲۳ جنوری شاه - فتاوی مسیح موعود : ۱۵ - الحکم ۲۳ اپریل تناه ، فتادی مسیح موعود من :
: ابو داؤد كتاب الصلوۃ باب اذا اقام بارض العدو يقصر ملكا - تحفة الفقهاء من.و: فتادی احمد یه م
شه :- باب صلوة المسافر اذا اجمع مكشات :
Page 198
۱۹۲
ا
"چونکہ سفر کے کوسوں دسانت کوس تین منزل، اور مدت رہائش دیتین روز اور چودہ روزہ ہمیں
بھی اختلاف ہے اس لئے جو قصر کرتے ہیں وہ قصر کریں اور جو نہیں کرتے وہ نہ کریں.ایک دوسرے
پر اعتراض نہ ہو یہ لے
اے
" اگر کہیں ٹھہرتا ہو اور پندرہ دن سے کم ٹھہرنا ہو تو بھی قصر کریں اور اگر پندرہ دن سے زیادہ
ٹھہرنا ہو تو پوری پڑھیں :
یہ میں نما نہ قصر کر کے پڑھاؤں گا.اور گو مجھے یہاں آئے چودہ دن ہو گئے ہیں مگر چونکہ علم
نہیں کہ کب واپس جانا ہوگا اس لئے میں نماز قصر کر کے ہی پڑھاؤں گا.حضرت مسیح موعود علیہ السلام
ایک دفعہ گورداسپور میں دوماہ سے زیادہ عرصہ تک قصر نماز پڑھتے رہے کیونکہ آپ
کو پتہ نہیں
تھا کہ کب واپس جانا ہوگا کہ
سوال: سفر کی کیا تعریف ہے.موجودہ زمانہ میںتو سفر کے لئے ہر قسم کی سہولتیں ہیں ؟
ہوا ہے.سفر کی حالت میں نماز قصر کرنے کا حکم دیا گیا ہے.اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے یہ تصریح کہیں نہیں
کی کہ فلاں سہولت ہو تو سفر نہیں ہوگا اور فلاں سہولت نہ ہو تو سفر ہو گا.اصل برکت اللہ تعالیٰ کے
حکم کی تعمیل میں ہے.اپنے پاس سے حجت بازی کرنے اور مسائل گھڑنے میں نہیں ہے.قصر کے
بارہ میں آیت قرآنی اور حدیث نبوی مع ترجمہ درج ذیل ہے :-
1
- وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَامٌ أَن تَقْصُرُوا
مِنَ الصَّلوة - ثه
جب تم ملک میں سفر کر د تو تمہیں کوئی گناہ نہیں کہ نماز کو چھوٹا
کر دو.۲ - حدیث یہ ہے :- كان ابن عباس يَقُولُ فَرَضَ اللَّهُ عَلَى نَتَكُمْ عَلَى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلّم فِي الْعَشْرِ ارْبَعًا وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ - له
یعنی حضرت ابن عباس
نے سے مردی ہے کہ للہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر خضر
میں چارہ رکعات اور سفر میں دو دو رکعت نما نہ فرض کی ہے.: الفضل ۲۲ اپریل ها شام سے : الفضل ۸ در مارچ م : ه: - ہدایہ اولین کتاب الصلواۃ باب صلاة المسافر ما : : ۱۸
: الفضل ۲۵ مئی ۹۴۳ ، الفضل : جولائی ۱۹۳۳ ، البدر یکم تم نشره ، ۲۳ جنوری شاه :
AQ
۵۵ : نساء : ۱۰۲ + : کشف الغمبر ص :
-
نه
Page 199
۱۹۳
سفری تاجر کی نماز
سوال : یکی اور میرے بھائی ہمیشہ تجارت عطریات وغیرہ میں سفر کرتے ہیں.نماز ہم دوگانہ
پڑھیں یا پوری ؟
ہواہے :.حضرت اقدس علیہ اسلام نے فرمایا.سفر تو وہ ہے جو ضرورتا گاہے بگا ہے ایک شخص کو
پیش آو ہے نہ یہ کہ اس کا پیشہ ہی یہ ہو آج یہاں کل وہاں اپنی تجارت کرتا پھرے.یہ تقویٰ
کے خلاف ہے کہ ایسا آدمی اپنے آپ کو مسافروں میں شامل کر کے ساری عمر نماز قصر کرنے میں ہی
گذار دے.اے
حکام کا دورہ سفر نہیں
حکام کا دورہ ایسا ہے جیسے کوئی اپنے باغ کی سیر کرتا ہے.خواہ نخواہ قصر کرنے کا تو کوئی وجود نہیں.اگر دوروں کی وجہ سے انسان قصر کر نے لگے تو پھر یہ دائمی قصر ہوگا جس کا کوئی ثبوت ہمارے پاس نہیں
ہے.حکام کہاں مسافر کہلا سکتے ہیں.سعدی نے بھی کہا ہے.منعم بکوه و دشت و بیابان غریب نیست
ہر جا کہ رفت خیمه زد و خوابگاه ساخت که
سوال :.مبلغین نے پوچھا کہ ہم سفر میں رہتے ہیں روزہ افطار اور نماز قصر کر سکتے ہیں یا نہیں ؟
جواب: - حضرت خلیفہ ایسیح الثانی نے فرمایا " سفر چھوٹا کہ دو.روزے برابر رکھو.یہ آپ لوگوں کا فرض
منصبی ہے اس لئے آپ سفر پر نہیں سمجھے جا سکتے ، سے
سوال:- داماد اپنے سسرال جا کہ پوری نماز پڑھے یا دوگانہ ؟
جواب : سسرال کا گھر بھی پردیس اور سفر کے حکم میں ہے.وہاں قصر نماز ہی پڑھنی چاہیئے.سوائے
اس کیے کہ وہاں اس کی اپنی جائیداد ہو اور وہ اسے اپنے گھر کی طرح سمجھتا ہو.اس صورت میں
اسے مقیم سمجھا جائے گا.- 1
بدر ۲۸ مارچ :
الحکم ۲۳ اپریل تشله ، فتاوی مسیح موعود شاه :
و الفضل ۱۶ جولائی ۱۹۱۳ :
-1
Page 200
۱۹۴
سوال : اگر مسافر امام کے ساتھ نماز میں اس وقت شامل ہو جب کہ امام پہلی دو رکعتیں پڑھ چکا ہو
تو کیا مسافر اپنی دو رکعت پڑھ کر امام کے ساتھ ہی سلام پھیر دے یا چار پڑھے ؟
جوا ہے :.جب مسافر مقیم امام کے ساتھ شامل ہو تو اس کو چاروں رکھتیں ہی پڑھنی چاہئیں لیے
سوال : سفر میں نماز قصر کرنا ضروری ہے یا اختیاری.اسی طرح سفر میں نمازوں کا جمع کرنا ضروری
ہے یا اختیاری؟
جوا ہے :.سفر میں نماز قصر کرنا ضروری ہے.جماعت احمدیہ کا مسلک یہی ہے.کیونکہ خدا نے اپنی رحمت
سے یہ ایک رعایت دی ہے اس لئے اس نعمت کی قدر کرنی چاہیئے.کیونکہ شکر نعمت واجب ہے
نیز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے عام صحابہ کرام اس کا التزام فرمایا کرتے تھے.علاوہ ازیں
بعض حدیثیوں سے معلوم ہوتا ہے کہ سفر کی اصل نمازہ ہی دو رکعت ہے صرف اقامت کی صورت میں
دورکعتوں کا اس پر اضافہ کیا گیا ہے.حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ :
" الصَّلوةُ أَوَّلُ مَا فُرِضَتْ رَكْعَتَانِ فَاقِرَّتْ صَلوةُ السَّفَرِ وَ
ا تَمَّتْ صَلوةُ الْحَضْر
پس جو اصل ہے اسے ترک کرنا درست نہیں.(۳) جمع کی بنیاد ضرورت پر ہے اس لئے یہ ایک اختیاری رعایت ہے یعنی اگر ضرورت اور مجبوری
ہو تو جمع کر لے ورنہ الگ الگ وقت پر پڑھے.کیونکہ اس میں اصل یہ ہے کہ ہر نماز اپنے اپنے
وقت پر پڑھی جائے.نیز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا طریق عمل نویں ذی الحجہ
کی نمازہ ظہر و عصر اور مغرب و عشاء کے علاوہ باقی ایام کی نمازوں میں جمع سے متعلق اختیاری امر
کی وضاحت کرتا ہے اور یہی سنت مسلمانوں میں رائج ہے.نماز خوف
حالت خوف مثلاً محاذ جنگ میں نماز قصر کرنے کی اجازت ہے.قصر کے معنے ہیں چھوٹا کرنا.چنانچہ
خوف کی حالت میں نماز مختصر ہو جاتی ہے.اس کی مختلف طریقے قرآن کریم اور احادیث میں بیان ہوئے
ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ میدان جنگ میں اگر زور کی لڑائی ہو رہی ہو یا دشمن کے حملے کا ڈر ہو یا فوج
مورچہ بند ہو تو ان سب صورتوں میں حسب حالات نماز کی رکھتیں کم ہو جاتی ہیں.ڈو کا موقع ہو تو دو ورنہ
ایک رکعت ہی کافی ہوگی.اگر حالات زیادہ خطرناک ہوں تو جماعت کی بجائے اکیلے اکیلے اور اگر اس کا
: الفضل ۲۳ جنوری سوله - فتاوی احمدیہ مثال به سه : - بخاری ابواب تقصیر الصلواة - باب يقصر اذا خرج منا ، ابو داؤد :
Page 201
۱۹۵
بھی موقع نہ ہو تو پھر چلتے پھرتے سواریا پیدل قبلہ کی طرف رُخ ہو یا نہ ہو محض اشارہ سے بھی نماز پڑھی جاسکتی
ہے اور اگر اتنی بھی زیادہ خطرناک حالات کا سامنا ہو تو نمانہ کی نیت کر لینا چند ایک کلمات ادا کرنا اور
ایک آدھ اشارہ کر لینا بھی کافی ہے.یوں جنگ میں کئی وقتوں کی نمازیں اکٹھی بھی کی جاسکتی ہیں
جنگ اور نماز
سوال :- میدان جنگ میں نمازہ کیسے پڑھیں؟
جواب :.جس طرح بن پڑے ہر حال میں پڑھ لو.چھوڑنا ہر گز نہیں چاہیئے.ایک سے زیادہ اوقات کی ملا کہ
ہی پڑھ سکو تو پڑھ لو.سے
سوال: میدان کارہ نہار میں قصر صلواۃ اور روزہ کے متعلق کیا حکم ہے ؟
جواب :.نماز قصر پڑھیں اور روزہ نہ رکھیں.سے
سوال : نماز سے متعلق کسی مسئلہ میں فوج ، سول سے مختلف بھی ہے یا نہیں ؟
جو اہے.فوج نمانہ کے معاملہ میں صرف اس حد تک عام سول آبادی سے مختلف ہے کہ وہ بحالات
مجبوری و ضرورت اپنے اپنے وقت میں نماز پڑھنے کی بجائے دو تین چار یا پانچ نمازیں اکٹھی یعنی
جمع کہ کے پڑھ سکتی ہے.اسی طرح اگر گھمسان کی جنگ ہو رہی ہو تو فوجی چلتے پھرتے حملہ کر تے
اشاروں اشاروں میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں.اس بارہ میں آیت و حدیث کا حوالہ درج ذیل ہے:
فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً اَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللهَ كَمَا
عَتَمَكُمْ مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ
:
حدیث یہ ہے :-
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَابِ جَاءَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ بَعْدَ
مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ جَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ وَقَالَ يَا رَسُولَ الله
ما لذت أن أصَلَى حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ أَن تَخْرُبَ - قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَا واللهِ مَا صَلَّيْتُهَا فَنَزَلْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم
بخاری کتاب المغازی باب غزوه خندق منه
1010
الفضل یکم جولائی شملہ سے :- الفضل ۲۰ جولائی شاوه له :- البقره : ۲۴۰ :
Page 202
194
بدحات فَتَوَضَّا لِلصَّلوة وتَوَضَّأَنَا لَهَا فَصَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ
الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَى بَعْدَهَا الْمَغْرِبَه
فوت شدہ نمازیں
فرض نماز وقت پر پڑھی جائے تو اسے ادا کہتے ہیں.لیکن اگر کسی وجہ سے مثلاً بھول جائے یا سویا
رہے اور وقت پر نماز نہ پڑھ سکے بلکہ بعد میں کسی وقت پڑھے تو اُسے قضاء کہتے ہیں سیکھ
فرض نمازوں کی قضاء واجب ہے جب یاد آئے یا موقع ملے یہ رہی ہوئی نماز پڑھ لی جائے.عمداً
نماز چھوڑنے کا تدارک صرف توبہ و استغفار ہے.قضاء میں نمازوں کی ترتیب کو قائم رکھنا بھی ضروری ہے
لیکن اگر ترتیب بھول جائے یا فوت شدہ نمازوں کی تعداد چھے سے زیادہ ہو جائے تو پھر ترتیب ضروری نہیں
رہتی.فجر کی دو سنتوں کے علاوہ باقی کسی نماز کی سنتوں کی قضاء نہیں.فوت شدہ نمازوں کی قضاء
سوال : اگر کوئی شخص کسی وقت نماز پڑھنا بھول جائے تو پھر کیا کرنے ؟
جواب :.جس وقت یاد آئے اس وقت پڑھ لے.کے
سوال : اگر ایک نما نہ چھوٹ جائے تو کیا ساری پچھلی نمازیں جاتی رہتی ہیں ؟
جواب : اگر کوئی نماز چھوٹ جائے تو اس کو تا ہی پہ استغفار کرے اور اس نماز کو دوبارہ پڑھے شید
سوال : میں چھ ماہ تک تارک صلواۃ تھا اب میں نے تو یہ کی ہے کیا وہ سب نمازیں اب پڑھوں ؟
-
-
جواب : اس طرح نماز کی قضاء نہیں ہوتی.اس کا علاج تو بہ ہی کافی ہے.تہ
سوال : ایک بیمار نے بارہ دن نماز نہ پڑھی تو اس کا بارہ تیرہ روپیہ کفارہ دیا کیا یہ درست ہے ؟
جواب : نماز جان بوجھ کر چھوڑی یا بیماری کی وجہ سے کئی روز نہ پڑھ سکا.دونوں صورتوں میں کوئی
کفارہ نہیں.صرف تو یہ کافی ہے یہ
: - بخاری البواب صلوة الخوف من ، كتاب
المغازی میده :
: بخاری باب قضاء الصلوات ما : سه :- ترمذی ابواب الصلوۃ باب في الرجل تفوت الصلوات بايتهن يبد أم :
1410
له الفضل در جولائی شه فائل مسائل دینی ۱۳۲۵ بدر ۴ در یک ایده به شه : الفضل دار مئی ۱۹۱۵ مهر
14-1-4
Page 203
194
قضاء عمری
سوال ہوا کہ جمعتہ الوداع کے دن لوگ چار رکعت نماز پڑھتے ہیں اور اس کا نام قضاء عمری رکھتے ہیں
اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ گذشتہ نمازیں جو ادا نہیں کیں ان کی تلافی ہو جا دے اس کا کوئی شور سے یا نہیں ؟
جواب: - حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا : " یہ ایک فضول امر ہے.مگر ایک دفعہ ایک شخص ہے وقت
نماز پڑھ رہا تھا کسی شخص نے حضرت علی نہ کو کہا کہ آپ خلیفہ وقت ہیں اسے منع کیوں نہیں کرتے؟
فرمایا کہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں اس آیت کے نیچے ملزم نہ بنا یا جاؤں :-
وتر
ادعيتَ الَّذِى يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى :
ہاں اگر کسی شخص نے عمداً نماز اس لئے ترک کی ہے کہ قضاء عمری کے دن پڑھ لوں گا تو اس نے
نا جائز کیا ہے اور اگر ندامت کے طور پر تدارک مافات کرتا ہے تو پڑھنے دو کیوں منع کرتے ہو آخر
دعا ہی کرتا ہے.ہاں اس میں پست ہمتی ضرور ہے پھر دیکھو منع کرنے سے کہیں تم بھی اس آیت
کے نیچے نہ آجاؤ " سے
و ترطاق کو کہتے ہیں اور اسے مراد یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد کم از کم تین رکعت نماز پڑھی جائے یہ
نماز واجب ہے وتر کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد علی الترتیب سورہ اعلیٰ سورہ کافرون اور سورہ
اخلاص پڑھنا مسنون ہے.تاہم کوئی دوسری سورہ بھی پڑھی جاسکتی ہے.وتر کی دوسری رکعت کے بعد
قعدہ میں بیٹھ کر تشہد پڑھے.پھر سلام پھیر کہ الہ اکبر کہتے ہوئے کھڑا ہو جائے اور تیسری رکعت پڑھے
یہ بھی جائز ہے کہ تشہد کے بعد اٹھ کر تیسری رکعت مکمل کرے اور پھر سلام پھیرا جائے.البتہ پہلی دکو
رکعت پڑھے بغیر صرف ایک رکعت پڑھنا پسندیدہ نہیں.وتر کی تیسری رکعت کے بعد دعائے قنوت
پڑھنا مسنون ہے.دعائے قنوت یہ ہے :-
له : - عن على انه رائ في المصلي اقوا ما يصلون قبل صلوة العيد فقال ما رأیت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يفعل ذالك فقيل له الا ننها هم نقال اخشى ان ندخل تحت وعيد وله تعالى القيت الذي ينهى عبدا
اذا صلی - تفسیر روح البیان به مطبوعہ تنبول ما له صورة علق ۱ - بن الحکم اور اپیل کشته فتاری می شود
Page 204
۱۹۸
اللهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِي نِيْمَنَ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِي فِيْمَنُ
تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ فَإِنَّكَ
تَقَفِى وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ إِنَّهُ لا يُذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ وَإِنَّهُ لَا يُحِزُّ مَنْ
مَا دَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبَ إِلَيْكَ
وَصَلَّى اللهُ عَلَى النَّبي له
یعنی اسے میرے اللہ مجھے ہدایت دے کہ ان لوگوں میں شامل کر جن کو ہدایت
دینے کا تو نے فیصلہ کیا ہے.اور مجھے سلامت رکھ کر ان لوگوں میں شامل کہ جن کو
سلامت رکھنے کا تو نے فیصلہ کیا ہے.اور مجھے دوست بنا کر ان لوگوں میں شامل کہ
جن کو دوست بنانے کا تو نے فیصلہ کیا ہے اور مجھے برکت دے ان العامات میں جو
تو نے دیئے ہیں.اور مجھے بچا ان چیزوں کے نقصان سے جو تیری تقدیر میں نقصان دہ
قرار دی گئیں ہیں.کیونکہ تو ہی فیصلے کرتا ہے اور تیری مرضی کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں
کیا جاسکتا.سو وہ شخص ذلیل و خوارہ نہیں رہ سکتا جس کا تو دوست ہے.اور نہ وہ عزت
پاسکتا ہے جس کا تو دشمن ہے.اسے ہمارے رب تو برکت والا اور بلند شان والا ہے
اسے اللہ ہمار سے نبی پر خاص فضل فرما جن کے ذریعہ سے ہمیں ایسی عمدہ دعاؤں کا علم
حاصل ہوا.- اللهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلْ عَلَيْكَ
وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ
مَنْ يَفْجُرُكَ اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ وَإِلَيْكَ نَسْعَى
وَنَحْفِدُ وَنَرْجُوا رَحْمَتَكَ وَنَخْشَى عَذَابَكَ إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ
ملحق لله
وتروں کا وقت نماز عشاء سے لیکر طلوع فجر تک رہتا ہے تاہم سونے کے بعد رات کے آخری حصہ
میں اُٹھ کر تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد وتر ادا کرنا افضل ہے.اگر رات کے آخری حصے میں اٹھنے کی عادت
نہ ہو تو عشاء کے بعد ہی وتر پڑھ لینے بہتر ہیں.دتر اکیلے پڑھے جاتے ہیں.البتہ رمضان المبارک میں وتر کی
نمانہ تراویح کی طرح باجماعت پڑھنا بھی مشروع ہے کیے
ا نسائی باب الدعا فی الوتر ص ، ابو داؤد ص ب له الف - قيام الليل ١٣٣٥ الشيخ محمد بن نصر المروزی متوقى شته
ب - اخرجه محمد بن نصر في كتاب قيام الليل بحوالہ تحفة الفقها باب صلاة الوتر ۳ مطبوعہ دار الفکر دمشق -
:- نور الايضاح باب الوتر ص ا ب
Page 205
194
نماز وتر سے تعلق فتاوی
ایک نماز دو تہ کہلاتی ہے اس نماز کی بھی مغرب کی طرح تین رکعتیں ہیں.مگر فرق یہ ہے کہ مغرب
کی نماز میں پہلے تشہد کے بعد جو تیسری رکعت پڑھی جاتی ہے اس میں سورہ فاتحہ کے بعد قرآن کریم
کی زائد تلاوت نہیں کی جاتی.لیکن وتر کی نماز میں تیسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد قرآن
کریم کی چند آیات یا کوئی چھوٹی سورۃ پڑھی جاتی ہے.دوسرا فرق اس میں یہ ہے کہ نما نہ وتر کو مغرب کی نماز کے برخلاف دو حصوں میں بھی تقسیم
کیا جا سکتا ہے.یعنی یہ بھی جائز ہے کہ دو رکعتیں پڑھ کر تشہد کے بعد سلام پھیر دیا جائے اور
پھر ایک رکعت الگ پڑھ کر تشہد کے بعد سلام پھیرا جائے.اے
سوال : کیا و تراس طرح پڑھے جا سکتے ہیں کہ تینوں رکھتیں اکٹھی پر بھی جائیں اور درمیان میں دو
رکعتوں کے بعد تشہد نہ بیٹھا جائے ؟
جواہ :- وتر کا زیادہ صحیح طریق یہ ہے کہ دو رکعت پڑھ کر تشہد بیٹھے پھر سلام پھیر دے.پھر کھڑا
ہو کر ایک رکعت پڑھے اور التحیات کے بعد سلام پھیرے یا دوسری رکعت کا تشہد پڑھ کہ
کھڑا ہو جائے اور تیسری رکعت پڑھے اور تشہد پڑھ کر سلام پھیر دے.لہ
سوال : حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا وتر پڑھنے کا کیا طریق تھا ؟
ہواہے : تفسیر القرآن مؤلفہ سید سرور شاہ صاحب کے منڈا پر حضور کے وتر پڑھنے کا طریق ہوں
درج ہے
" وتروں کی نسبت بہت سوال ہوتا رہتا ہے کہ ایک پڑھا جائے یا تین اور
یہ بھی اگر تین ہوں تو پھر کس طرح پڑھے جائیں تو ان میں حضور کا حکم یہ ہے کہ
ایک رکعت تو منع ہے اور تین اس طور پر پڑھتے ہیں کہ دو رکعتوں کے بعد
التحیات پڑھ کر سلام پھیر دیتے ہیں اور پھر اُٹھ کر ایک رکعت پڑھتے ہیں اور
کبھی دو کے بعد التحیات پڑھتے ہیں اور سلام پھیرنے سے پہلے اُٹھ کر
تیسری رکعت پڑھتے ہیں.سے
له : تفسير سورة بقره تفسير كبير جلد اول ص : - الفضل ۱۵ ار ستمبر ۱۹۳۵ :
سے : مجموعه فناوی من :
Page 206
حضرت خلیفہ اول کا ارشاد بھی یہی ہے.اے
سوال :.اکیلا وتر پڑھنے کے متعلق کیا حکم ہے ؟
جو اسے :.ہم نے اکیپ لار وتر پڑھنے کے متعلق حکم کہیں نہیں دیکھا.ہاں دو رکعت کے بعد خواہ سلام
پھیر کر دوسری رکعت پڑھ لے خواہ تینوں رکعت ایک ہی نیت سے پڑھ لے.سے
حدیث کی تصریح یہ ہے :-
مَنْ عَائِشَةَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلّى فِيْمَـ
بَيْنَ أَن يَفْرُغُ مِنْ صَلوةِ الْعِشَاءِ إِلَى الْفَجْرِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً
يُسَه وَ سلم بَيْنَ كُلِّ رَكَعَتَيْنِ وَيُوتِرُ بِوَاحِـ وَاحِدَةٍ - ٥٣
وتر پڑھنے کا وقت
سوال: - و ترکس وقت پڑھنے چاہئیں؟
جواب : راز حضرت خلیفہ اول و تر پہلی رات کو پڑھ لینا بہتر ہے.پچھلی رات بھی پڑھے جا سکتے ہیں.بہت ہے کہ پہلی رات پڑھ لئے جائیں.حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہی طریق عمل ہے کہ
آپ پہلی رات کو پڑھ لیا کرتے تھے.سے
سوال :.وتر کی نماز عشاء کا جزو ہے یا نما نہ تہجد کا.اگر مغرب اور عشاء جمع ہوں تو وتر پڑھنے کیوں
ضروری سمجھے جاتے ہیں جبکہ جمع کی صورت میں فرض کے علاوہ کوئی اور نمازہ دسنتیں وغیرہ نہیں
پڑھی جاتی ؟
جواب : اصل میں تو وتر نما نہ تہجد کا جزو ہیں یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد کی آخری تین
رکعتوں کو وتر کی صورت میں ادا فرمایا کرتے تھے لیکن چونکہ وتر نماز کی الگ بھی تاکید آئی ہے
اور ہر ایک شخص نماز تہجد کے لئے نہیں اُٹھتا.یا کسی عوارض کی وجہ سے اٹھ نہیں سکتا.اسلئے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ ایسا شخص نماز عشاء کے بعد سونے سے پہلے
وتر کی نمازہ پڑھ لیا کرے.حدیث درج ذیل ہے :
ا قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ اَوْصَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْوِتْرِ
-
ه بدر ۱۲ جنوری شاه :
PA
: بدر ۲ اپریل ۱۹۰۳ :
: - مسلم باب صلوۃ اليل وعدد ركعات النبی صل اللہ علی وم قلت له : - بدر ۱۳ جنوری نشده ، نقادی مسیح موعود منت :
Page 207
٢٠١
- μ
قَبْلَ النَّوْمِ.- عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ خَانَ
ان لا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيَوْتِرَ أَوَّلَهُ وَمَنْ أَنْ يَقُومَ آخَرَهُ
فَلْيُوتِرُ آخِرَ اللَّيْلِ » له
اس لحاظ سے وتر کی نماز کا وقت عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک ہے.حدیث میں ہے :-
٣ - عَنْ خَارِجَةَ بْنِ حُذَافَةَ أَنَّهُ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ اللهَ أَمَرَكُمْ بِصَلُوةٍ هِيَ خَيْرُ تَكُمْ
مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ الوِ تَرجَعَلَهُ اللهُ نَكُمْ فِيْمَا بَيْنَ صَلوةِ الْعِشَاءِ
إِلَى أَنْ يُطْلِعَ الْفَجْرُ - له
جمع نماز کی صورت میں اگرچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بالتصریح یہ ثابت نہیں کہ حضور
مغرب کے ساتھ عشاء کی نماز کو جمع کرنے کے معا بعد وتر کی نماز پڑھ لیا کرتے تھے اور ایسی تصریح
آبھی نہیں سکتی کیونکہ حضور علیہ السلام کو بالعموم وتر کی نماز تہجد کے ساتھ آخری حصہ رات میں ادا
فرمایا کرتے تھے.تاہم اصول عامہ کے مطابق اگر کوئی شخص چاہے تو جمع نمازہ کے معا بعد وتر کی نمازہ
پڑھ سکتا ہے اور ہماری جماعت کا عام عمل اسی کے مطابق ہے.عام طور پر جمع نماز کے بعد سنتیں
اور نوافل نہیں پڑھے جاتے.البتہ وتر ضروری ہیں کیونکہ وتر کے متعلق سنتوں سے زیادہ تاکید
آئی ہے.اسی لئے علماء نے وتر کو واجب قرار دیا ہے جو سنت سے اُوپر کا درجہ ہے.سفر میں وتر
سوال : سفر میں وتر کی کتنی رکعت پڑھنی چاہئیں ؟
جواب :- (از حضرت خلیفہ بہیج اول سفر و حضر میں وتر کے واسطے تین رکعت ضروری ہیں.حضرت
مسیح موعود علیہ السلام سفر میں بھی و ترکی تین رکعت بعد نماز عشاء پہلی رات کو ضرور پڑھا کرتے ہیں.ہے
ه بخاری باب ساعات الوتر الخ م : مسلم باب من خاف ان لا يقوم من آخر الليل الا من ٢٩ :
۳ : ترمذی ابواب الوترصت باب فضل الوتر : --- بدر ۱۲ جنوری شاه :
Page 208
٢٠٢
وتر اور قرأة سور
عَن أبي ابْنِ كَعْتُ رَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْوِتْرِ
بِسبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى وَفِي الرَّيْعَةِ الثَّانِيَةِ بِقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ.وَفي الثَّالِثَةِ بِقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ وَلَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِي الْآخِرَةِ -
یعنی حضرت ابی بن کعب کا بیان ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی پہلی رکعت میں سورہ مسلم
اسم ربک الاعلی پڑھتے.دوسری میں سورہ کافرون اور تیسری میں سورہ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ
سلام صرف آخر میں تینوں رکعت پڑھ کر پھیر تھے.والے.وتر نماز کی آخری رکعت میں دعائے قنوت پڑھنا اگر بھول جائے تو سجدہ سہو واجب ہے
یا نہیں؟
جواہے :.سجدہ سہو واجب نہیں.کیونکہ دنروں میں بالالتزام دعاء قنوت پڑھنا ہمارے نزدیک اجب
اور ضروری نہیں ہے بلکہ مستحب اور باعث ثواب ہے.وتروں کے بعد نفل
سوال :.وتر ادا کرنے کے بعد نوافل پڑھے جا سکتے ہیں یا نہیں اور اگر نوافل پڑھے جا سکتے ہیں تو
کیا دوبارہ وتر پڑھنے ضروری ہیں ؟
جواب :.عشاء کی نمازہ اور وتر پڑھنے کے بعد طلوع فجر سے پہلے نوافل پڑھے جا سکتے ہیں اس میں
کوئی شرعی روک نہیں.تاہم بہتر یہی ہے کہ نوافل وتر کی نماز سے پہلے ادا کئے جائیں اور رات
کی نقل نمازہ کا اختتام و تم پر کیا جائے.حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا :-
اِجْعَلُوا آخِرَ صَلوتِكُمْ مِنَ اللَّيْلِ وَثرًا " له
کہ رات کی آخری نماز وتر ہونی چاہیئے لیکن اگر کوئی عشاء کی نمازہ کے ساتھ ہی وتر پڑھ لے اور پھر تجت
کے وقت اُٹھ کر نوافل پڑھے تو ضروری نہیں کہ وہ دوبارہ وتر بھی پڑھے.حضرت ابو بکر اور کئی
نسائی کتاب قيام الليل باب القرأة في الوتر ص :
-:: مسلم باب صلوة الليل مثنى مثنى والوتر من آخر الليل مثنت :
Page 209
٢٠٣
جلیل القدر صحابہؓ کا یہی مسلک تھا کہ وہ بعد میں دوبارہ وتر پڑھنے کو ناپسند کرتے تھے.ہاں حضرت
ابن عمریضہ اور چند ایک دوسرے علماء کی رائے یہ ہے کہ پچھلی رات نوافل پڑھنے کے بعد دوبارہ وتر
کی نماز پڑھنا مستحسن ہے اور اس کی صورت یہ ہے کہ پچھلی رات اُٹھ کر پہلے صرف ایک رکعت
پڑھے.یہ رکعت رات کے پہلے حصہ میں پڑھی ہوئی وتر کی ایک رکعت کے ساتھ مل کر دو رکعت
نقل یعنی دوگانہ بن جائے گی اس کے بعد اور نوافل پڑھے اور پھر آخر میں دو رکعت کے ساتھ ایک
مزید رکعت پڑھ کر اُسے وتر بنائے.چنانچہ ابن عمر سے روایت ہے :-
انهُ كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنِ الْوِتْرِ قَالَ أَمَّا رَنَا فَلَوْ أَوْ تَرْتُ قَبْلَ أَنْ
أنَامَ ثُمَّ اَرَدْتُ اَنْ اُصَلَى بِاللَّيْلِ شَفَعْتُ بِوَاحِدَةٍ مَا مَضَى
مِن وِتْرِى ثُمَّ صَلَّيْتُ مَثْنى مَثْنَى فَإِذَا قَضَيْتُ صَلَاتِي اَوْ تَرَتُ
بواحدَةٍ لِاَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَن يُجْعَلَ
آخِرُ صَلَاةِ اللَّيْلِ الْوِتْرَه
کہ اگر میں سونے سے پہلے وتر پڑھ لوں اور پھر رات کے آخری حصہ میں تہجد کے لئے اُٹھوں تو
پہلے میں ایک رکعت پڑھتا ہوں اور اس طرح رات کے پہلے حصہ کے وتر کو شفع یعنی دوگانہ بنا
لیتا ہوں.پھر دو دو رکعت کر کے نفل پڑھتا رہتا ہوں اور آخر میں ایک رکعت وتر پڑھتا ہوں.اسی طرح حضرت علی نہ کی روایت ہے :-
قَالَ الوِتْرُ ثَلَاثَهُ انْوَاعِ فَمَنْ شَاءَ أَنْ يُوْتِرَ أَوَّلَ اللَّيْلِ اَوْتَرَ
قیانِ اسْتَيْقَظَ نَشَاءَ أَنْ يَشْفَعَهَا بِرَكْنَةِ وَيُصَلَّى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى
يُصْبِحَ ثُمَّ يُوتِرَ وَإِن شَاءَ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى يُصْبِحَ وَإِنْ شَاءَ آخَرَ اللَّيْلِ
یعنی و تریپر ھنے کی تین صورتیں ہیں.اول یہ کہ رات کے پہلے حصہ میں ہی وتر پڑھ لے اور
پھر بعد میں تہجد کے لئے اُٹھے تو صرف نماز تہجد ہی پڑھے اور دوبارہ وتر نہ پڑھے.دوئم یہ کہ سو کر اٹھنے کے بعد ایک رکعت پڑھ کر پہلے وتر کو شفع یعنی جفت بنا ہے.پھر
دو دو رکعت تہجد پڑھتا رہے اور آخر میں پھر ایک رکعت وتر کی پڑھ لے.سوئم.یہ کہ وتر کی نماز سونے سے پہلے نہ پڑھے بلکہ تہجد کے بعد آخر میں پڑھے.جو بزرگ رات کے آخری حصہ میں دوبارہ وتر پڑھنے کو پسند نہیں کرتے ان کے دلائل یہ ہیں :.ے : مسند احمد یا نیل الاوطار من باب لا وتران في ليلة : : مسند امام شافی بحوالہ نیل الاوطار باب لا و توان في ليلة هي :
Page 210
الف: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کبھی نہیں کیا.ہے :.حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ ایک رات میں دو دفعہ وتر نہ پڑھے جائیں اور صورت
مذکورہ میں تو ایک طرح سے تین دفعہ وتر پڑھنے کی شکل بن جاتی ہے.ج :.یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک رکعت تو سونے سے پہلے پڑھی جائے اور پھر درمیان میں
انسان سوئے.پیشاب پاخانہ کرے.باتیں کر ہے.وضو کر ہے اور پھر ایک رکعت
پڑھے اور وہ پہلے پڑھی ہوئی رکعت کا حصہ بن کر دو رکعت کی ایک نماز یعنی دوگا نہ شمار ہو
اصول نماز میں ہمیں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی.د - آخری نماز ہونے کا حکم عمومی ہے لازمی نہیں.کیونکہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ و ہم بعض اوقات
وتروں کے بعد دو رکعت نفل میٹھے کہ پڑھا کرتے تھے.جیسا کہ مندرجہ ذیل حدیث سے ثابت
ہوتا ہے :-
عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ سُئِلَتْ عَائِشَةُ مَنْ صَلوةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ كَانَ يُصَلَّى ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلَّى ثَمَانِ
رَكَعَاتٍ ثُمَّ يُوتِرُ ثُمَّ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ فَإِذَا أَرَادَ انْ
يَرْكَعَ قَامَ فَرَكَعَ ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ المَدَاءِ وَالْإِقَامَةِ مِنَ
صلاة الصبح له
پس ضروری نہیں کہ رات کی آخری نمازہ کو و تر بنانے کے لئے یہ حیلہ اختیار کیا جائے.تاہم
اگر کوئی چاہیے تو حضرت ابن عمرہ کے مسلک کو اختیار کرتے ہوئے ایسا کر سکتا ہے.وتر با جماعة
سوال : - رمضان المبارک میں تراویح کے ساتھ وہ بھی باجماعت پڑھے جاتے ہیں.کیا ایسا کرنا ضروری
ہے؟
جواب : رمضان المبارک میں وتر کی نماز باجماعت ادا کرنے کے بارہ میں بعض احادیث سے استنباط
-
ہوتا ہے.مثلاً
1 - أَخْرَجَ ابْنُ حَمَان فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّم صَلَى بِهِمْ ثَمَانِ رَكَعَاتٍ ثُمَّ ارْتَرَ - ٢
له يسلم باب جواز النافلة قائما وقامدا ص :
نیل الاوطار باب صلاة التراويح من
Page 211
۲۰۵
کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو آٹھ رکعت نماز پڑھائی اور پھر وتر پڑھائے.عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ انَّهُ قَالَ أَمَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَابِ ابى بن
كَعْب وَتَمَيْمَ الدَّارِي أَنْ يَقُومَا لِلنَّاسِ بِاحْذَى عَشَرَةً رَكْعَة - له
یعنی حضرت عمر نے ابی بن کعبے اور تمیم داری کو فرمایا کہ وہ لوگوں کو گیارہ رکعت ڈیموں وتر )
تراویح پڑھایا کریں.أخْرَجَ ابو داود ان ابي بن كَعْبٍ كَانَ يُؤْتُهُمْ فِي التَّرَادِيمِ وَ
يقنت في النِّصْفِ الْآخِرِ مِنْ رَمَضَانَ - له
یعنی حضرت ابی تراویح پڑھاتے اور رمضان کے نصف آخر میں وتروں میں قنوت
بھی پڑھتے.ان احادیث کی بناء پر ائمہ فقہ رمضان المبارک میں وتر با جماعت کو جائز سمجھتے ہیں.چنانچہ
حنفیوں کی مشہور
کتاب ہدایہ میں ہے:
لا يُصَلى الوِثر بجمَاعَةٍ فِي غَيْرِ رَمَضَانَ عَلَيْهِ إِجْمَاعُ الْمُسْلِمِينَ له
سوال:- وتر نماز کی قضاء کی جائے یا نہیں ؟
ہوا ہے :.فرضوں کی قضاء ضروری ہوتی ہے.وتروں کی قضاء اس طرح ضروری تو نہیں لیکن پڑھنا
اولیٰ ہے.طلوع فجر کے بعد نماز سے پہلے پہلے بھی اور سورج نکلنے کے بعد بھی جس وقت چاہیے
وتروں کی قضاء کر سکتا ہے.حدیث کے الفاظ یہ ہیں :-
(1)
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَمْ يُصَلِ
مِنَ اللَّيْلِ مَنَعَهُ مِن ذَلِكَ النَّوْمُ ادْ غَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ صَلَّى مِنَ النَّهَارِ
ثنى عَشْرَةَ رَكْعَة له
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم
مَنْ خَامَ عَنِ الْوِتْرِ اَوْ نَسِيَهُ نَلْيُصَلِ إِذَا ذَكَرَ وَإِذَا اسْتَيْقَظَ له
ته
یعنی.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سو جانے کی وجہ سے وتر نہیں پڑھ سکا وہ
جاگنے پر جب یاد آئیں وتر پڑھ لئے.موطا امام مالك باب الترغيب في الصلواة في رمضان من : ه: - حاشیه شرح وقایہ ص :
ه هدایه ، فصل فی قیام رمضان هنا :
: ترندی البواب الوتر باب في الرجل ينام عن الاترص :
ترمذی ابواب صلواة الليل من ب
Page 212
نماز تہجد
۲۰۶
عشاء کی نمازہ کے بعد سوجانا اور پھر پچھلی رات اٹھ کر عبادت
کرنا اور نماز پڑھنا باعث برکت ہے.راست
کا آخری حصہ بالخصوص قبولیت دعا اور تقرب الی اللہ کا بہت بڑا ذریعہ ہے کیونکہ اس وقت انسان اپنی سیٹھی
نیند اور آرام دہ بستر کو چھوڑ کر اپنے مولائے حقیقی کے حضور سجدہ ریز ہوتا ہے.اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے :-
وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةٌ لَكَ له
(
اور رات کو بھی تو اس (قرآن کے ذریعہ سے کچھ سو لینے کے بعد شب بیداری کیا کر.(٣) يَا يُّهَا الْمُزَّمَلُ : قَمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلاً هُ نِصْفَاةَ ونَقَمَن مِنْهُ قَلِيْلًا 8 ادْ زِدْ
عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً له
اسے چادر میں لیٹے ہوئے (خدا کی رحمت کا انتظار کرنے والے، راتوں کو اُٹھ اُٹھ کے عبادت
کہ جیسی ہماری مراد یہ ہے کہ رات کا اکثر حصہ عبادت میں گزارہ اگر عینی اسکا نصف یا
نصف سے کچھ کم کر دے یا اس پر کچھ اور بڑھا دے.اور قرآن کو خوش الحانی سے پڑھا کر.تہجد کی نماز آٹھ رکعت ہے.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ یہ نماز پڑھی ہے.آپ تہجد کی نماز
بالعموم دو دو رکعت کر کے پڑھتے تھے.لمبی قرأت اور لیے لینے رکوع و سجود کے علاوہ خوب ٹائیں کرتے.پھر
آخر میں تین رکعت وتر ادا فرماتے.اس طرح سے آپ بالعموم رات کے پچھلے حصہ میں کل گیارہ رکعت نماز
پڑھا کرتے تھے.حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے.” ہماری جماعت کو چاہیے کہ وہ تہجد کی نمازہ کو لازم کرلیں جو زیادہ نہیں وہ دو رکعت ہی
پڑھ لے.کیونکہ اس کو ڈھا کرنے کا موقع مل جاوے گا.اس وقت کی دعاؤں میں ایک خاص تاثیر
ہوتی ہے کیونکہ وہ بچے درد اور بچے جوش سے نکلتی ہیں جب تک ایک خاص سوزا اور درد دل
نہ ہو اس وقت ایک شخص خواب راحت سے بیدار کب ہو سکتا ہے.پس اس وقت کا
اُٹھنا ہی ایک درد دل پیدا کر دیتا ہے جسے دُعا میں رقت اور اضطراب کی کیفیت پیدا
ہو جاتی ہے.لیکن اگر اٹھنے میں سستی اور غفلت سے کام لیتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ درد
ر
اور سوز دل میں نہیں کیونکہ نیند تو غم کو دور کر دیتی ہے لیکن جبکہ نیند سے بیدار ہوتا ہے
تو معلوم ہوا کہ کوئی درد اور غم نیند سے بھی بڑھ کر ہے جو بیدار کر رہا ہے.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کثرت سے نوافل ادا کرتے آپ آٹھ رکعت نماز نفل
۱۵۴
: بنی اسرائیل: ۲۸۰ -:- مزمل ۲۱تا۵ به ۱۹۳ - بخاری باب قیام النبی صلی اللہ علیہ وسلم با الليل ص 12 سه :
Page 213
اور تین وتر پڑھتے کبھی ایک ہی وقت میں ان کو پڑھ لیتے اور کبھی اس طرح سے ادا کرتے
که دورکعت پڑھ لیتے اور پھر سو جاتے اور پھر اُٹھنے اور دو رکعت پڑھ لیتے اور سو جاتے
غرض سو کمر اور اُٹھ کر نوافل اس طرح ادا کرتے " لے
نوافل میں سے نماز تہجد اعلیٰ ارفع اور سب سے زیادہ مؤکدہ نماز ہے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے اس پر مداومت فرمائی ہے.اللہ تعالیٰ نے اس میں بے اندازہ برکات رکھی ہیں اور قرآن
پاک میں اس کی طرف خاص طور پر توجہ دلائی ہے.نماز تہجد کی آٹھ رکعتیں ہیں اور وتروں سمیت
گیارہ رکعتیں.اس کا وقت نماز عشاء کے بعد سو کہ کسی وقت اُٹھنے سے لے کر صبح صادق کے
طلوع ہونے تک ہے.اس وقت میں جب چاہے نیند سے بیدار ہو کہ یہ تمہانہ ادا کر سے لیکن زیادہ
بہتر یہ ہے کہ شروع رات میں جلد سو جائے اور پھر رات کی آخری تہائی میں اٹھ کہ یہ نماز ادا کر ہے.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارہ میں روایت ہے کہ : -
كان يصلى ثلاث عشرة ركعة يصلى ثمان ركعات ثم يوتر ثم يصلى
ركعتين وهو جالس فاذا اراد ان يركع قام تركع ثم یصلی رکعتین بین
النداء والاقامة من صلاة الصبح - له
یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت کل تیرہ رکعت اس طرح پڑھتے تھے کہ پہلے دو
دو کر کے آٹھ رکعت پڑھتے پھر تین وتر پڑھتے پھر بیٹھ کر دو رکعت پڑھتے اس کے
بعد جب اذان ہوتی تو دو رکعت سنت فجر ادا فرماتے.اگر و تریا تہجد کی نمازہ فوت ہو جائے تو بعد میں کسی وقت ان کی قضاء کی جا سکتی ہے.یہ قضاء
جائزہ اور موجب ثواب ہے.ضروری نہیں.تے
حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں :-
" تہجد کے فوت ہونے یا سفر سے واپس آکر پڑھنا ثابت ہے.لیکن تعبد میں کوشش
کرنا اور کریم کے دروازے پر پڑے رہنا مین سنت ہے.وَاذْكُرُوا اللهَ كَثِيرًا
لعَلَّكُمْ تُفْلِحُون لم
۲۸۳
له : - الحکم اپریل سنشاه ، فتاوی مسیح موعود مت : : مسلم ص ۲۱ طه
ه: انیل الاوطار باب قضاء مالفوت من الوتر والسنن الخصب ہے (۲) نیل الاوطار ما جاء في قيام الليل من :
:- سورۃ انفال آیت ۴۶ :
: - مکتوبات احمد یہ جلد اول صنت فتاوی مسیح موعود طلا
Page 214
۲۰۸
اگر کوئی شخص بیمار ہو یا کوئی ایسی وجہ ہو کہ وہ تہجد کے نوافل ادا نہ کر سکے تو وہ اٹھ کر
استغفار درود شریف اور الحمد شریف ہی پڑھ لیا کر ہے ؟ لے
نماز تراویح
نماز تراویح در اصل تہجد ہی کی نماز ہے صرف رمضان المبارک میں اس کے فائدہ کو عام کرنے
کے لئے رات کے پہلے حصہ میں یعنی عشاء کی نماز کے معا بعد عام لوگوں
کو پڑھنے کی اجازت دی گئی
ہے اس نماز کا زیادہ تر رواج حضرت عمر کے زمانہ میں پڑا.رمضان میں بھی رات کے آخری حصہ
میں یہ نماز ادا کرنا افضل ہے.نماز تراویح میں قرآن کریم سنانے کا طریق بھی صحابہ رضوان اللہ علیہم کے زمانہ سے چلا آیا
ہے.تراویح کی نماز آٹھ رکعت ہے تاہم اگر کوئی چاہے تو بینی یا اس زیادہ رکعت بھی پڑھ
سکتا ہے.ہر چار رکعت کے بعد تھوڑی دیر کے لئے سستا لینا مستحب
سوال : - تراویح کے متعلق معرض ہوا کہ جب یہ تہجد ہے تو بینش رکعت پڑھنے کی نسبت کیا ارشاد
ہے کیونکہ تہجد تو مع د تر گیارہ یا تیرہ رکعت ہے ؟
جو اسے میں فرمایا :.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دائمی تو وہی آٹھ رکعات ہیں.اور آپ تہجد کے
وقت ہی پڑھا کرتے تھے اور یہی افضل ہے مگر پہلی رات بھی پڑھ لینا جائز ہے.ایک رات ہے
میں ہے کہ آپنے رات کے اول حصہ میں اسے پڑھا.۲۰ رکعات بعد میں پڑھی گئیں مگر آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت وہی تھی جو پہلے بیان ہوئی.سے
(۲) تراویح کی رکعتوں کے بارہ میں اصولاً یہ بات یاد رکھنی چاہیئے کہ ہمارے نزدیک خاص تعداد
کی پابندی ضروری نہیں اگر کوئی آٹھ رکھتوں کی بجائے بنیں رکھتیں پڑھتا ہے تو اس پر
اعتراض نہیں کرنا چاہیے.روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمریض کے زمانہ میں بیس رکعت تراویح
بھی پڑھائی گئی ہے لیکن جہاں تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دوامی عمل کا تعلق ہے آپ اکثر
آٹھ رکعت ہی پڑھتے تھے.اور تہجد کے وقت میں پڑھتے تھے.حدیث کے الفاظ یہ ہیں :-
مکتوبات احمدیہ حب الحکم اپریل نشده، قنادی مسیح موعود طنت سے :.مسند احمد مانیل الاوطار حیات ، نصب الرايه
۱ - ۳: البدر هر فروری خنشله ، فتاوی مسیح موعود منت :
Page 215
۲۰۹
عَنْ ابْن سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ كَيْفَ كَانَتْ صَلوةٌ
رسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ قَالَتْ مَا كَانَ يَزِيدُ فِي
رَمَضَانَ وَلَا فِى غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشَرَةَ رَكْعَةً يصلي أربعا فلا قتال
عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَ ثُمَّ يُصَلِّى اَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ
وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا - له
یعنی ابو سلمان نے حضرت عائشہ ان سے پوچھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم رمضان
المبارک میں رات کے
وقت کتنی رکعت نماز پڑھتے تھے.آپ نے فرمایا رمضان ہو یا غیر رمضان آپ گیارہ رکعت سے
زیادہ نہیں پڑھتے تھے.چار رکعت پڑی لمبی اور بڑی عمدگی سے پڑھتے پھر چار رکوت بڑی لمبی اور بڑی
عمدگی سے پڑھتے.اس کے بعد تین وتر پڑھتے.گویا اٹھ رکعت الگ اور زمین الگ.ایک اور روایت میں ہے:
انَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم خَرَجَ لَيْلَةٌ مِنْ جَوْنِ اللَّيْلِ
فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِه
اس روایت سے ظاہر ہے کہ آٹھ رکعت تراویح پڑھنا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت
کے مطابق ہے باقی چونکہ تراویح نفل نماز ہے اس لئے اگر کوئی زیادہ رکعت پڑھنا چاہے تو وہ
ایسا کر سکتا ہے.چنانچہ حضرت عمر اور حضرت عثمان کے زمانہ میں لوگ بیس رکعت پڑھنے لگے
تھے تاکہ ہر رکعت کی قرأت جلدی جلدی ختم ہو اور ایک ہی رکعت میں لوگوں کو دیر تک نہ کھڑا ہونا
پڑے.کیونکہ لمبی قرأت کی وجہ سے بعض اوقات لوگ تھک جاتے تھے.تے
سوال : - اگر کسی مقام پر حافظ قرآن میسر نہ آئے تو کیا نماز تراویح میں امام کا قرآن مجید ہاتھ میں پکڑ کر دیکھ
دیکھ کر تلاوت کرنا اور اس طرح نماز پڑھانا درست ہے ؟
ہوا ہے.تراویح میں قرآن کریم سے دیکھ کہ تلاوت کرنا یا کسی مقتدی کا قرآن دیکھ کر امام کے بولنے پر لقمہ
دنیا عام حالات میں مناسب نہیں اسی قرآن کریم کے حفظ کرنے کا شوق کم ہو گا.امام ابو حنیفہ کے نزدیک تو ایسا کرنے سے نماز فاسد ہو جائے گی.ہاں اگر مجبوری ہے اور
شه بخاری باب قام النبی صل اللہ علی وسلم باليل ته مسلم باب الترغیب فی قیام رمضان ما به
۱۵۴
1
تفصیل کے لئے دیکھیں نصب الراية في تخريج عاديث الهدایه صدا :
Page 216
۲۱۰
حالات کا تقاضا ہے کہ تراویح کی سنت کا احیاء کیا جائے تو اس شاذ صورت میں اس کی اجازت
مرکزہ سے لی جا سکتی ہے.چنانچہ ایسے ہی حالات کے پیش نظر سابقہ ائمہ میں سے مندرجہ ذیل نے
اس طریق کے اختیار کرنے کی اجازت دی ہے.امام مالک، امام شافعی اور امام احمد - شه
بعض اثار میں آتا ہے کہ حضرت عثمان ” جب نفل پڑھتے تو اپنے پاس ایک آدمی کو بٹھا لیتے
جب پڑھتے پڑھتے بھول جاتے تو وہ آدمی آپ کو صحیح آیت بتلا دیتا.اسی طرح حضرت انس ف نوافل
پڑھتے ہوئے اپنے غلام کو قرآن کریم دے کر اپنے پہلو میں بٹھا لیتے جب بھولتے تو وہ غلام آپ
کو بتاتا جاتا.کہ
اسی طرح حضرت عائشہ کے غلام ذکوان قرآن کریم سامنے رکھ کر نفل نماز پڑھاتے اور حضرت
عائشہ بہ مقتدی ہوتیں کہیے
پس مجبوری کے حالات میں قرآن سے دیکھ کہ نفل نماز میں قرأة جائز ہے اسی طرح قرآن کریم
کے ورق الٹنا اور اس کے لئے ہاتھ سینہ سے ہٹانا بھی جائز ہے.سوال :.رمضان کے مہینہ میں اگر مغرب کی نماز میں بارش ہو رہی ہو تو کیا مغرب اور عشاء کی نمازیں جمع
ہو سکتی ہیں جبکہ تراویح کا باقاعدہ انتظام ہو ؟
جواب : رمضان کے مہینہ میں ضرورت کے پیش نظر بمطابق فیصلہ حاضر احباب مغرب و عشاء کی نمازیں جمع
کرنے میں کوئی حرج نہیں.اگر تراویح پڑھنا ہو تو نمازیں جمع کرنے کے معا بعد پڑھی جا سکتی ہیں.یا جو
لوگ ٹھہر سکیں وہ کافی رات گزر نے پر پڑھ لیں.اصولاً اس تقدیم و تاخیر یں کوئی شرعی امر مانع نہیں.سوال : نماز تراویح کے اختتام پر جو شیرینی تقسیم کی جاتی ہے بعض احباب اس کو جائز قرار نہیں دیتے
اصل حکم کیا ہے ؟
جواب :.ایسے امور کو رواج نہ ہی دیا جائے تو بہتر ہے کیونکہ دینی معاملہ میں وہی امر قابل اعتماد ہے جس
کی بنیاد قرآن و حدیث پر ہو ورنہ روز نئی نئی بدعات کے درواز سے کھلتے رہیں گے اور بے اصولی
بڑھے گی.نماز کسوف و خسوف
سورج گرہن کو کسوف اور چاند گرہن کو خوف کہتے ہیں.اجرام فلکی میں یہ طبعی تبدیلی انسان کو اس طرف
ل كتاب الميزان للشعراني صبا لها كشف الغمه ها و قیام الليل لشيخ محمد بن نصر مزوری به بخاری باب عامة العبد:
Page 217
۲۱۱
متوجہ کرتی ہے کہ جس طرح حالات کے تغیر نے سورج اور چاند کی روشنی کو کم دیا ہے اسی طرح مختلف عوارض
سے دل کے نور کو بھی گہن لگ سکتا ہے اور اسے صرف اللہ تعالیٰ کا فضل ہی بچا سکتا ہے سو اس فضل
کے حصول اور روحانی مدارج میں ترقی کی طرف توجہ دلانے کے لئے کسوف و خسوف کے موقع پر دورکعت نماز
رکھی گئی ہے.شہر کے سب لوگ مسجد یا کھلے میدان میں جمع ہو کہ یہ نمازیں پڑھیں تو زیادہ ثواب ہوگا.نماز با جماعت
کی صورت میں قرآت بالجہر اور نبی ہونی چاہیئے.حسب حالات ہر رکعت میں کم از کم دو رکوع وبعض روایات
میں تین رکوع بھی آئے ہیں، کئے جائیں.یعنی قرآت کے بعد رکوع کیا جائے پھر قرآن کا کچھ حصہ پڑھا جائے
اس کے بعد دوسرا رکوع کیا جائے اور پھر سجدہ ہو.اس نماز کے رکوع و سجود بھی لیے ہونے چاہئیں نماز
کے بعد امام خطبہ دے جس میں تو بہ و استغفار اور اصلاح حال کی تلقین کی جائے.لہ
نماز استسقاء
قحط سالی اور بارش کی قلت کی صورت میں خدا تعالیٰ کے فضل کو جذب کرتے اور اس کے رحم کو
جوش میں لانے کے لئے لوگ دن کے وقت کھلے میدان میں جمع ہوں.امام ایک چادر اوڑھے ہوئے
دو رکعت نماز پڑھائے.قرأت بالجہر ہو.نماز سے فارغ ہونے پر امام اونچے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ
سے الحاج اور عاجزی کے ساتھ یہ مسنون دعا مانگے :-
اللهُمَّ اسْقِنَا غَيْئًا مُغِيْنَا مَرِيَّا مَرِيعا نَافِعًا غَيْرَ ضَارٌ.عَاجِلاً
غَيْرَ آجِل - اَللّهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ وَبَهَائِمَّكَ وَانْتُر رَحْمَتَكَ وَ
اجي بَلَدَكَ الْمَيِّتَ اللهُمَّ اسْقِنَا اللَّهُمَّ اسْقِنَا اللَّهُمَّ اسْقِنَا - لَه
یعنی اسے اللہ ہم کو پانی پر برسنے والا گھبراہٹ دور کرنے والا ، فائدہ دینے والا.ضر نہ دینے والا.جلد آنے والا دیر نہ کرنے والا.اسے اللہ پانی پلا اپنے بندوں کو اپنے
جانوروں کو اور پھیلا اپنی رحمت کو اور زندہ کر اپنے اس مردہ علاقہ کو اسے اللہ ہم کو پانی
پلا.اسے اللہ ہم کو پانی پلا.اسے اللہ ہم کو پانی پلا.ے :.ترمذی ابواب الصلوة باب ماجاء في صلاة الكسوف (1) (ابو داؤد کتاب الكسوف ص ١٧ :
ه -: - ابو داؤد كتاب الصلوۃ باب صلوة الاستسقاء ص۱۳ (۳)
Page 218
۲۱۳
درود شریف - استغفار اور دعا کر نے کے بعد امام اپنی چادر الٹائے.یہ ایک رنگ میں گویا نیک
قال لینا ہے اور تصویری زبان میں اللہ تعالیٰ سے التجاء کرنا ہے کہ اسے میرے خدا جس طرح میں نے
چادر کو الٹا دیا ہے اسی طرح تو قحط سالی کے نا گفتہ بہ اور پریشان کن حالات کو بدل دے لے
نماز استخاره
ہر اہم دینی اور دنیوی کام شروع کر نے سے پہلے اس کے بابرکت ہوتے اور کامیابی کے ساتھ
اس سے عہدہ بیرہ ہونے کے لئے دعا کی جائے.طلب خیر کی مناسبت سے اسے " صلوۃ الاستخاره
کہتے ہیں.رات سونے سے پہلے دو رکعت نفل پڑھے جائیں.سورہ فاتحہ کے علاوہ پہلی رکعت میں سورۃ
کافرون اور دوسری میں سورہ اخلاص پڑھنا مسنون ہے.قعدہ میں تشہد.درود شریف اور ادعیہ مسنونہ
کے بعد عجز و انکسار کے ساتھ مندرجہ ذیل دعا پڑھنا مسنون ہے :-
:
اللهم إنّي َاسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَاسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَ
استانكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا اقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا اَعْلَمُ
وَااَنْتَ عَلَامُ الْغُيُوب - اللهُمَّ إِن كُنتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرُ لِي
في دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِى فَاقْدِرُهُ فِي وَيَسِّرُهُ لِى ثُمَّ
بَارِكْ لِى فِيْهِ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرُّ فِي فِي دِينِي وَ
معَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِى فَاصْرِفَهُ عَنِى وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدِرْ لِي
الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ ارْضِنِي بِهِ - لَه
یعنی اے اللہ میں بھلائی چاہتا ہوں جو تیرے علم میں ہے اور قدرت چاہتا ہوں جو تیری
توفیق سے ہی مل سکتی ہے اور مانگتا ہوں تیرے بڑے فضلوں کو کیونکہ تو طاقت رکھتا ہے
اور میں طاقت نہیں رکھتا اور تو جانتا ہے اور میں نہیں جانتا اور تو تمام غیب کی باتوں کو
جاننے والا ہے.اسے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام جو مجھے درپیش ہے دکام کا نام بھی ہے
سکتا ہے، میرے لئے دین اور دنیا میں اور انجام کے لحاظ سے بہتر ہے تو اس کو میرے
واسطے مقدر فرما اور اس کو میرے لئے آسان کر دے.پھر میرے لئے اس میں برکت ڈال ہے
اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے دین اور میری دنیا کے لئے اور انجام کے لحاظ سے مضر ہے
تو اس کو مجھ سے دُور ہٹا دے اور مجھ کو اس دُور رکھ اور میرے لئے بھلائی مقدر فرما
ابو داؤد كتاب الصلوۃ باب صلاة الاستسقاء ص بمس : يتجارى كتاب الدعوات باب الدعاء عند الاستخارة
و ترمذی ، ابن ماجد کتاب الصلوة باب صلواة الاستخارة مثث :
Page 219
۲۱۳
جہاں کہیں بھی وہ ہو اور پھر اس بارہ میں تجھے تسکین و رضا عطا فرما.ستید نا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوة والسلام فرماتے ہیں :." آج کل اکثر مسلمانوں نے استخارہ کی سنت کو ترک کر دیا ہے حالانکہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم پیش آمدہ امر میں استخارہ فرما لیا کر تے تھے.سلف صالحین کا بھی یہی
طریق تھا.چونکہ دہریت کی ہوا پھیلی ہوئی ہے اس لئے لوگ اپنے علم و فضل پر نازاں ہو کہ
کوئی کام شروع کر لیتے ہیں اور پھر نہاں در یہاں اسباب سے جن کا انہیں علم نہیں ہوتا ہے
نقصان اٹھاتے ہیں.اصل میں یہ استخارہ ان یک رسومات کی عوض میں رائج کیا گیا تھا جو مشرک
لوگ کسی کام کی ابتداء سے پہلے کہتے تھے.لیکن اب مسلمان اسے بھول گئے حلانکہ استخارہ
سے ایک عقل سلیم عطاء ہوتی ہے جس کے مطابق کام کرنے سے کامیابی حاصل ہوتی ہے “ لے
صلوة الحاجة
اگر کسی شخص کو کوئی حاجت یا ضرورت در پیش ہو کسی سے کوئی کام نکلوانا ہو تو اس کے لئے دُعا کا ایک
طریق جو حدیث میں بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اچھی طرح وضوء کر کے دورکعت نماز پڑھی جائے.نماز سے
فارغ ہو کر ثنا ء اور درود پڑھے اور پھر مندرجہ ذیل دعا مانگے تو اللّہ تعالیٰ کے فضل سے امید ہے کہ وہ اس
کی ضرورت کے پورا کر نے کے سامان کر دے گا.اور انشاء اللہ تعالیٰ اس کا کام ہو جائے گا.دعا یہ ہے:.لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْعَلِيْمُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ.اَلحَمدُ
لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - اَسْتَالُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِهِ مَغْفِرَتِكَ
وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلّ بِرٍ وَ السَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمَ - لَا تَدَعْ لِي ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ
وَلَا هَمَّا الَّا خَرَجْتَهُ وَلَا حَاجَةٌ هِي لَكَ رَضًا إِلَّا قَضَيْتَهَا يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمينَ ؟
یعنی اللہ تعالٰی کے سوا کوئی معبود نہیں وہ حلم والا اور کرم والا ہے.اللہ تعالیٰ پاک ہے اور عرش
عظیم کا مالک ہے.سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے نہیں جو رب العلمین ہے.اسے اللہ
میں تجھ سے تیری رحمت کے سامان چاہتا ہوں اور تیری مغفرت کے وسائل مانگتا ہوں.ہر سیسکی سے وافر حصے اور ہر گناہ سے بچنے کی درخواست کرتا ہوں.میرا کوئی گناہ نہ رہے
تو سب بخش دئے.کوئی غم نہ رہے تو سب دُور کر دے اور میری ہر ضرورت جس پر تو
له : البدر ۳ در خون شده ، فتادی مسیح موعود ص: ۲: ترندی کتاب الصلاة باب صلواة الحاجة ما
Page 220
۲۱۴
خوش ہے پوری کر دے.اسے سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کر نے والے :
نماز اشراق
نیزہ بھر سورج نکل آنے کے بعد دو رکعت نماز پڑھنا اس کے بعد جب دھوپ اچھی طرح نکل آئے
اور گرمی کچھ بڑھ جائے تو چار رکعت یا آٹھ رکعت پڑھنا.بعض روایات سے ثابت ہے.پہلی دو رکعت کو
صلوۃ الاشراق اور اس کے بعد کی نماز کو صلوۃ الضحی کہا گیا ہے.صلوۃ الاوابین بھی اسی زمانہ کا نام ہے.بعض کے نزدیک مغرب کے بعد جو نوافل ادا کئے جاتے ہیں انہی نوافل کا دوسرا نام صلوۃ الا وا بین ہی ہے
بہر حال یہ نفل نماز پڑھنے کا ثواب احادیث سے ثابت ہے.پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے اشراق کی رکعات پر مداومت ثابت نہیں مگر آپ کو جب موقع ملنا آپ
انہیں ادا کرتے تھے.نماز اشراق کا وقت سورج کے طلوع ہونے اور نیزہ دو نیزہ بلند ہو جانے پر شروع ہوتا
ہے اور قریبا دو بجے دن تک رہتا ہے.اس کی رکعتیں دو چار - آٹھ یا بارہ تک ہیں.اس کے مطابق جتنی
رکھتیں کوئی چاہے پڑھ لے.اس نماز کو صلوۃ الاوابین اور صلوۃ الضحیٰ بھی کہتے ہیں.اگر کوئی شخص ذرا سویر سے اشراق کی نماز چار رکعت پڑھ لے اور پھر نو یا دس بجے کے قریب چار رکعت
مزید نفل پڑھے تو اس دوسری نمازہ کو چاشت کی نماز یا صلواۃ الضحی کہیں گے.حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق تھا کہ جن دنوں کوئی خاص مصروفیت نہ ہوتی آپ کبھی کبھی صبح کی نماز پڑھ کر مسجد
ہی میں تشریف رکھتے اور جب سورج طلوع ہونے کے بعد اتنا بلند ہو جاتا جتنا کہ مغرب سے پہلے عصر کی
نماز کے آخری وقت بلند ہوتا ہے.یعنی دو اڑھائی نیزہ کے براہمہ تو آپ چار رکعت نفل ادا فرماتے.پھر جب سورج اتنا بلند ہو جاتا جتنا پچھلے پہر ظہر کے آخری وقت میں ہوتا ہے جسے پنجابی میں چھا دیلا"
کہتے ہیں تو آپ مزید چار رکعت نفل ادا فرمائے.اس حدیث کو ترمذی وغیرہ نے بیان کیا ہے.بہر حال یہ نمازہ گا ہے گا ہے کی ہے.اس کے لئے کوئی خاص پابندی یا اہتمام ثابت نہیں.سوال: کیا نماز اشراق اور اڈا بین علیحدہ علیحدہ نمازیں ہیں یا دونوں ایک ہی ہیں اور کس طرح اور
کس وقت پڑھی جاتی ہیں؟
له : - قیام اللیل شیخ محمد بن نصر مروزی ملت ، مثث :
له : - تريزی کتاب الصلوة باب كيف كان يتطوع النبي صلى الله عليه وسلم بالنهار :
Page 221
۲۱۵
جواہے :- نماز اشراق ، نماز ضحی اور نماز اوابین میں اصولا کچھ فرق نہیں.سب نعلی نمازہ کے نام ہیں.جب سورج اچھی طرح چڑھ آئے اور دھوپ چمک اُٹھے تو اشراق کی نماز ادا کی جائے.چنانچہ
حدیث میں آتا ہے :-
صَلوةُ الْإِشْرَاقِ وَهِيَ رَكْعَتَانِ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم
يُصَلَّيْهَا إِذَا ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ مِن مَّطْلِعِهَا قَيْدَرُ مَعَ أَوْ رُمْحَيْنِ
وَكَانَ ابْن عَبَاسَ يَقُولُ صَلوةُ الْإِشْرَانِ هِيَ صَلوةُ الضَّحَى - له
عَن زَيْدِ بْنِ ارْتَم قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيَّاءِ وَسَلَّمَ عَلَى
أهْلِ تُبَاءَ وَهُمْ يُصَلُّونَ الضُّحَى فَقَالَ صَلوةُ الاَ وَابِيْنِ إِذَا
رمَضَتِ الْفِصَالُ مِنَ الضُّحى - له
تاہم ایک مرسل حدیث سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ مغرب کے بعد اور عشاء سے پہلے جو چھ
رکعت نوافل پڑھے جاتے ہیں وہ صلوٰۃ الاوابین ہیں.کے
صلاة التسبيح
تریزی اور بعض دوسری کتب حدیث میں صلوۃ تسبیح کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے.یہ نفلی نماز ہے
حسب فرصت و توفیق روزانہ ہفتہ یا سال یا عمر بھر میں ایک بار اوقات مکروہ کے علاوہ کسی وقت بھی یہ
چار رکعت نماز پڑھی جاسکتی ہے.ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ اور کوئی دوسری سورۃ پڑھنے کے بعد پندرہ
دفعہ سُبحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ ہے.پھر رکوع میں تسبیحات کے
بعد یہی ذکرہ دستی بار دہرائے پھر رکوع سے کھڑے ہو گر تسمیع و تحمید کے بعد پھر ہر سجدہ میں تسبیحات
کے بعد.پھر ڈھائے بین السجدتین کے بعد.اس کے علاوہ ہر رکعت کے دوسرے سجدہ کے بعد بیٹھ کر
دوستل دستی دفعہ یہی مندرجہ بالا ذکر کر ہے.اس طرح گویا ایک رکعت میں پچہتر بار اور چار رکعتوں میں
تین تو بار یہ ذکر دہرایا جائے گا.کہ
نوافل کے بارہ میں یہ اصول ہمیشہ مد نظر رہنا چاہیئے کہ ان کی اہمیت فرائض کے بعد ہے اور ان کا
کشف العمر ص: ه: مسلم کتاب الصلوۃ باب صلواة الأوابين حين ترميض الفصال ما:
باب من
ہے :- نیل الاوطان باب ماجاء في الصلاة بين العشاءين ميه : : - تمندی کتاب الصلواة با صلوة التبيح :
Page 222
۲۱۶
فائدہ تبھی ہے جبکہ انسان حقوق اللہ اور حقوق العباد سے متعلق ہرقسم کے فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی کرنے والا
نہ ہو.بہر حال صلوٰۃ التسبیح ایک نفل نماز ہے چاہے کوئی پڑھے چاہے نہ پڑھے.سوال : - کیا صلوۃ التسبیح باجماعت ادا کی جا سکتی ہے؟
جواب : - جہاں تک صلاۃ التسبیح کا تعلق ہے احادیث سے اس کا جواز ثابت ہے بلکہ اس کی ترغیب دی
گئی ہے.لیکن یہ ایک انفرادی اور خلوت کی نماز ہے اس کے لئے جماعت نہ مسنون ہے نہ
معروف.حضور علیہ السلام کے صحابہ یا آپ کے بروز کامل حضرت مسیح موعود علیہ السلام یا آپ کے
خلفاء و صحابہ نے اس نماز کے باجماعت ادا کرنے کو کبھی پسند نہیں کیا.اس لئے یہ نماز اسی حد
کے اندر رہ کر ادا کرنی چاہئیے جس حد کی وضاحت احادیث میں آئی ہے.سوال:- نماز تسبیح اور قضاء عمری میں کیا فرق ہے ؟
جواہ:.نماز تسبیح اور قضاء عمری میں سند کے لحاظ سے تو یہ فرق ہے کہ نماز تسبیح کی سند صحاح ستہ
میں موجود ہے.گو درجہ کے لحاظ سے وہ دوسری احادیث کے مقابلہ میں کمزور ہے.لیکن قضاء
عمری کی کوئی معتبر سند موجود نہیں.دوسرے نماز تسبیح میں ایسا کوئی تصور نہیں کہ یہ فرائض کے
قائمقام ہے لیکن قضاء عمری کے پس منظر میں یہ تصور ہے کہ یہ فوت شدہ فرائض کا ٹھیک ٹھیک
مداوا ہے.حالانکہ شرعی اصول کے لحاظ سے یہ ایک بالکل غلط تصور ہے.سجدہ تلاوت
قرآن کریم کی مندرجہ ذیل چودہ آیات میں سے کسی ایک کی تلاوت کرتے وقت یا گنتے وقت انسان خواہ
کھڑا ہو یا بیٹھا اسے سجدہ میں گو جانا چاہئیے.اس طرح سجدہ کرنے کو سجدہ تلاوت کہتے ہیں.یہ سجدہ
جتنا جلدی بجالایا جا سکے اُتنا ہی اچھا ہے.یہاں تک کہ اس کے لئے وضو کا ہونا بھی کوئی ایسا ضروری
کا ایسا
نہیں.اس سجدہ میں تسبیحات مسنونہ کے علاوہ یہ دعا پڑھنا احادیث میں مروی ہے :
سَجَدَ وَجْهِيَ لِلَّذِى خَلَقَهُ وَشَقَ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوتِهِ
میرا چہرہ سجدہ ریزہ ہے اس ذات کے سامنے جنسی اسے پیدا کیا اور اپنی قدرت خاص
سے اسے سننے اور دیکھنے کی قوت عطا کی.نیز یہ دُعا بھی پڑھ سکتا ہے:.اللهُم سَجَدَ لَكَ سَوَادِي وَآمَنَ بِكَ فُؤَادِي - يا
: - ترمذی باب ما يقول في سجود القرآن منت :
Page 223
۲۱۷
سجدَ لَكَ رُوحِي وَجَنَانِي.امام الصلوۃ اگر نماز میں یا نماز کے بعد سجدہ تلاوت کر سے تو مقتدی بھی ساتھ سجدہ کریں.آیات
سجدہ کی نشان دہی درج ذیل ہے :-
(1)
(۲)
(۴)
وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ - (سورۃ اعراف : ۲۰۰ )
بالْغُدُةِ وَالْآصَالِ (سورة رعد (۱۶) (۳) وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ.(سورة نحل (۵۱)
تھا..وَيَزِيدُهُمْ خَشُوعًا - ربنی اسرائیل: ۱۱۰ (۵) خر واستجدا وبكيا (مریم : ۵۹)
إن الله يَفْعَلُ مَا يَشَاء رمج : 19) بعض کے نزدیک سورہ حج میں دو سجدے میں دوسرا سجدہ
ذیل کی آیت پر ہے : وافعلوا الْغَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.( : )
وَزَادَهُمْ نُفُوراً - (الفرقان : (۶) (۸) هُوَرَبُّ الْعَرْشِنِ الْعَظِيمِ - (نمل (۲۰) -
-
ነ
(9) وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ - (السجده : ۱۶) (۱۰) خر راليا و انابه ((۲۵)
(1) وَهُمَلا يَسْتَمُونَ، حم سجده (۳۹) (۳) فَاسْجُدُ وَاللهِ وَاعْبُدُوهُ.(نجم :۶۳)
(۱۳) لا يسجدون (سورة الشقاق : ۲۲) (۳) وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبُ.(سوره علق: ۲۰)
سوال :.نماز کے دوران سجدہ تلاوت کس طرح کیا جائے ؟
جواب : سجدہ تلاوت کرنے کا طریق یہ ہے کہ جو نہی آیت سجدہ کی تلاوت ختم ہو اللہ اکبر کہتے ہوئے
سجدہ میں گر جائے.تین بار سبحان ربی الا علی کہے چاہے تو اور کوئی دُعا کر سے جیسا کہ بعض
ادعیہ کا ذکر ہوچکا ہے.اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ سے اُٹھے.نماز میں اگر آیت سجدہ کی تلاوت کی جائے تو آیت پڑھتے ہی سجدہ کیا جائے لیکن یہ بھی جائزہ
ہے کہ آیت ختم کرتے ہی رکوع میں چلا جائے اس صورت میں نہ رکوع اس سجدہ تلاوت کا بدل
بن جائے گا.اگر ایک وقت یا ایک مجلس میں ایک آیت سجدہ کو کئی بار دہرائے یا مختلف آیات
سجدہ پڑھے تو سب کے لئے ایک سجدہ کافی ہوگا.لیکن اگر ہر آیت پڑھنے کے بعد جگہ بدل نے
یا وقفہ کے بعد مختلف اوقات میں پڑھے تو پھر ہر قرأت کے لئے الگ سجدہ کرنا چاہیے.سوال :.سجدہ تلاوت کے بارہ میں کیا حکم ہے؟
جواب :.امام ابو ظیفہ کے نزدیک سجدہ تلاوت واجب ہے.دیگر ائمہ مثلاً امام شافعی امام مالک
کے نز دیک سنت ہے.اس سلسلہ میں بخاری کی مندرجہ ذیل روایات قابل غور ہیں.عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَرَأَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سُورَةَ التَّحْلِ حَقَ جَاءَ
Page 224
۲۱۸
السجدَةَ فَنَزَلَ فَسَجَدَ وَ سَجَدَ النَّاسُ حَتَّى إِذَا كَانَتِ الْجُمْعَهُ
القَابِلَةُ قَرَأَ بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءَ سَجِدَةً قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنْمَا نَمُتُ
بِالسُّجُودِ فَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ رَصَابَ وَمَنْ لَمْ يَسْجُدُ فَلَا اثم عليه
ولمسجد عُمَرُ وَزَادَ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ انَّ اللهَ لَم يَفْرِضِ
السجودَ إِلا أَن نَّشَاء له
شه بخاری باب من راى ان الله عز وجل لم
Page 225
۲۱۹
آداب مسجد
مسجد خُدا کا گھر ہے اس میں نماز اور ذکر الہی ہونا چاہیئے.دنیوی معاملات سے متعلق باتیں نہیں
کرنی چاہئیں.اسی طرح شور بھی نہیں ہونا چاہئیے.مساجد صاف ستھری ہوں صفیں پاک ہوں مسجد
میں خوشبو جلانا بھی مستحسن ہے.اسی طرح مسجد میں صاف کپڑے پہن کر اور خوشبو لگا کر جانا پسندیدہ
ہے اور کوئی ایسی چیز نہیں کھا کر جانا چاہیے جیسے بو آتی ہو سکا پیاز.لہسن اور مولی وغیرہ لیے
مسجد میں داخل ہونے اور نکلنے کی دُعا یہ ہے :-
بسمِ اللهِ الصَّلوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُونِي
وَافْتَحَ لِي ابْوَابَ رَحْمَتِكَ.اللہ کے نام کے ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلامتی ہو.اسے میرے
اللہ میرے گناہ بخش اور میرے لئے اپنی رحمت اور فضل کے دروازہ سے کھول دے سکے
سوال : مسجد زیر تعمیر ہے.کیا عورتوں کے لئے مسجد کے دائیں پہلو جگہ بنائی جائے یا بائیں پہلو ؟
جوا ہے :.اصل حکم جو احادیث سے ثابت ہے اور ائمہ فقہ میں متفق علیہ ہے وہ یہ ہے کہ عورتوں کی صفیں
مردوں کی صفوں کے پیچھے ہوں لیکن ایسا کرنے میں اگر کوئی وقت ہو اور پیچھے کی بجائے پہلو میں جگہ
متعین کرنی پڑے تو پھر مردوں کی مصنفوں سے بائیں جانب جگہ متعین کرنا زیادہ بہتر ہوگا.گو یہ ضروری
نہیں.سابق ائمہ یا حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے عورتوں کی صف پہلو میں بنانے کے بارہ میں
کوئی تصریح نہیں مل سکی.قادیان کی مسجد اقصیٰ میں عورتوں کی صف بائیں جانب اور مسجد مبارک میں دائیں جانب ہوا
کرتی تھی.اور اب ربوہ کی مسجد مبارک میں بائیں جانب اور مسجد اقصی میں اوپر کی گیلیری میں پیچھے
اور دائیں و بائیں صفیں بنتی ہیں.له : مسلم كتاب الصلوة باب نهى من اكل ثو ما أو بصلا اوكرانا او نحوها.من مصری به
سے : - ترمذی ابواب الصلاة باب ما يقول عند وحوله المسجد ص.
Page 226
سوال: کیا مسجد کا صحن مسجد کا حصہ ہوتا ہے ؟
جواہے : جس جگہ کی حد بندی اس غرض سے کر دی جائے کہ یہ مسجد ہے یہاں لوگ نماز پڑھیں اور
اس کی عام اجازت ہوا اور لوگ اس جگہ میں نماز پڑھنا شروع کر دیں تو یہ جگہ مسجد کہلائے گی
مسجد کے لئے یہ ضروری نہیں کہ اس پر چھت بھی ہو.مسجد حرام جو سب سے بڑی اور افضل
ترین مسجد ہے اس کا اکثر حصہ بصورت ضمن چھت کے بغیر ہے.حدیثوں میں آتا ہے.کہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بعض اوقات مسجد کے صحن میں خیمے نصب کر کے ان میں
رہائش اختیار کی جاتی تھی.جیسا کہ حضرت سعد بن معاذ کے لئے جبکہ وہ جنگ میں زخمی ہو گئے
تھے مسجد میں خیمہ نصب کیا گیا تھائیے
ظاہر ہے کہ یہ خیمہ چھت والے حصہ کے اندر نصب نہیں کیا گیا تھا.اسی طرح مسلمانوں
کا چودہ سو سالہ تعامل اس امر کی واضح دلیل ہے کہ صحن مسجد کا ہی حصہ ہے.سوال :.جیسا کہ عام مسلمانوں کا معمول ہے کہ جہاں بھی کچھ عرصہ قیام کریں اس جگہ جائے نماند (مسجد
انی طور پر تجویز کیا کرتے ہیں.کیا ایسی جگہ مستقل مسجد کا حکم رکھتی ہے اور اس کی خرید و فروخت منع
ہوا ہے : مسجد جس کی خرید و فروخت منع ہے وہ ، وہ ہے جو باقاعدہ پبلک مسجد ہو.اُسے بنانے
والے نے اپنے ملک سے نکال کر وقف عام کیا ہو اور قومی ملکیت میں آکر ہر شخص کا حق اس
پر قائم ہو چکا ہو.لیکن جو جائے نماز عارضی طور پر بنائی گئی ہے وہ باقاعدہ مسجد نہیں.ضرورت
پڑنے پر اُسے گرایا جا سکتا ہے.اور فروخت بھی کیا جا سکتا ہے.اس میں شرعاً کوئی ممانعت
نہیں.حکومت کی ملکیت پبلک جگہ میں جو مسجد بنائی بجائے اس کے لئے حکومت سے اجازت
حاصل کرنا بھی ضروری ہے.ورنہ وہ باقاعدہ مسجد نہ ہوگی.اور حکومت کو اُسے ضبط کر لینے کا
اختیار ہوگا.کیونکہ مالک کی اجازت کے بغیر کسی کی زمین پر قبضہ ناجائز متصور ہوتا ہے.مسجد کی جگہ تبدیل کرنا
سوال : کیا ہے آباد مسجد کو گرا کر اس جگہ کوئی اور عمارت تعمیر کر سکتے ہیں.کیا مسجد کی جگہ تبدیل
ہو سکتی ہے ؟
جوا ہے :.اہم ضرورت اور عوام کی سہولت کے پیش نظر مقامی جماعت کے فیصلہ اور مرکز کی اجازت
له : بخاری کتاب المغازی باب مرجع النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الاحزاب طلال :
Page 227
۲۲۱
کے بعد مسجد کی جگہ تبدیل کرنا اور اس کے طلبہ کو فروخت کر کے اسے مسجد کی ضروریات میں صرف
کرنا جماعت احمدیہ کے مسلک کے مطابق جائز ہے کیونکہ مفاد عامہ اور نمازیوں کی جائز سہولت
کو بہر حال ترجیح حاصل ہے.سابق ائمہ اور علماء میں اس کے متعلق اختلاف ہے.عام حنفیوں کا خیال یہ ہے کہ ایسا
کرنا جائز نہیں خواہ آبادی کے منتقل ہو جانے کی وجہ سے مسجد ویران ہی کیوں نہ ہو گئی ہو.ان
کی بنیاد یہ حدیث ہے :-
لا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا تُبْتَاعُ وَلَا تُوْهَبُ وَلَا تُوْرَتُ.جنبلی یعنی امام احمد بن حنبل کے متبعین اسے جائز سمجھتے ہیں.جنفی ائمہ میں سے امام محمد بھی اس
رائے سے متفق ہیں.مزید حوالے درج ذیل ہیں :-
الفت : -
اِنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلى سَعْدِ لَمَّا بَلَغَهُ أَنَّهُ قَدْ نُقِبَ بَيْتُ الْمَالِ
الَّذِي بِالكُونَةِ انْقُلِ الْمَسْجِدَ الَّذِى بِالثَّمَارِينَ وَاجْعَلْ
بَيْتَ الْمَالِ فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَإِنَّهُ لَقَ يَزَالَ فِي الْمَسْجِدِ
مُصَل وَكَانَ هَذَا مَشْهَدِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَلَمْ يَظْهرُ خِلَافَةَ
فكان إجماعا له
ب : - قَالَ الْحَنَابِلَةُ إِذَا نَتَقَلَ اَهْلُ الْقَرْيَةِ عَنِ الْمَسْجِدِ وَصَارَ
فِي مَوْضِعِ لَا يُصَلَّى فِيهِ وضَاقَ بِأَهْلِهِ وَلَمْ يُمْكِن تُوَسِيعُهُ
وَلَا عِمَارَةً بَعْضِهِ إِلَّا بِبَيْعِ بَعْضِهِ جَازَ - وَإِنْ لَمْ يَكُنِ
الانْتِفَاعُ بِشَيْءٍ إِلَّا بِبَيْعِ يُبَاءُ - که
ج : مَسْجِدٌ انْتَقَلَ اَهْلُ الْقَرْيَةٍ عَنْهُ وَصَارَ فِي مَوْضِع لا يُصَلى
فِيْهِ أَوْضَاقَ بِأَهْلِهِ وَلَمْ يَكُن تَوْسِيعُهُ فِي مَوْضِعِ او
تَشَعَبَ جَمِيعُهُ فَلَا تُمْكَنُ عِمَارَتُهُ وَلَا عِمَارَةُ بَعْضِهِ إِلَّا
بِبَيْعِ بَعْضِهِ جَازَ بَيْعَ بَعْضِهِ لِتَعْمَرَ بِهِ بَقِيَّتُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنِ
ه المعنى لابن قدامه جلده :
: المغنى باب الوقف مشده جلده
: - الاحوال الشخصية على مذاهب الخمسة من مؤلف محمد جواد مغنیه مطبوعہ بیروت ۳ ئه :
Page 228
۲۴۲
الانْتِفَاعُ بِشَيُّ مِنْهُ بَيْعَ جَمِيعُة - ب
د : وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ إِذَا خَرِبَ الْمَسْجِدُ أو الوَقْفُ عَادَ إلى
مِلْكِ وَاقِفِهِ لِأَنَّ الْوَتُفَ انْمَا هُوَ تَسْبِيلُ الْمَنْفَعَةِ فَإِذَا
زَالَتْ مَنْفَعَتُهُ زَالَ حَقٌّ الْمَوْتُوفِ عَلَيْهِ مِنْهُ فَزَالَ مِنكُهُ عَنْهُ يه
مسجد کی جگہ یا مسجد کا طلبہ فروخت کرنے کی ممانعت کی اصل وجہ یہ ہے کہ اس طرح کہیں مسجد
کے اموال پر ناجائز تصرف کی راہ نہ کھل جائے.لیکن اگر اس قسم کا کوئی خدشہ نہ ہو اور مسجد کا
علیہ جماعت کے باہمی مشورہ سے فروخت کیا جائے اور اس کا فروخت کرنا مسجد کے لئے
سود مند ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں اور نہ کوئی گناہ ہے.سوال : - ایک شخص نے مسجد بنانے کے لئے جگہ دی لیکن اُسے مسجد کی بجائے عام بیٹھنے کی جگہ بنا
دیا گیا.کیا یہ جائز ہے ؟
ہواہے :.جو زمین مسجد کی غرض سے دی گئی ہے وہ مسجد کے لئے ہی صرف ہونی چاہیئے اور مرکز کی
اجازت کے بغیر اسے کسی اور اجتماعی مقصد کے لئے استعمال نہیں کرنا چاہیئے.خصوصا یک
یہ کنندہ اس کے لئے راضی بھی نہ ہو.سوال.ایک عورت نے مسجد بنانے کے لئے زمین دی مسجد وہاں پر تعمیر ہوئی لیکن اب وہ گیر چکی
ہے.اس جگہ کی بجائے اب قریب ہی کھلی جگہ میں مسجد بنائی گئی ہے.کیا پہلی مسجد کی جگہ میں
معلم کے لئے کوارٹر بنا سکتے ہیں ؟
جواب :.صورت مذکورہ کے مطابق اس جگہ پر جہاں مسجد تھی اور اب گر گئی ہے اور اس کی بجائے
دوسری جگہ مسجد بنائی گئی ہے مقامی جماعت کے باہمی مشورہ اور مرکز سے اجازت حاصل کرنے
کے بعد اس قسم کی کوئی عمارت تعمیر کی جاسکتی ہے جو اجتماعی مقاصد کے کام آئے مثلاً اسکول
یا لائبریری کے لئے یا معلم اور مرتی کی رہائیش کے لئے اسے استعمال کیا جاسکتا ہے.اس میں
کوئی شرعی روک نہیں ہے.سوال :.ہمارے گاؤں میں ہماری مسجد بہت چھوٹی اور کچھ ہے.چھوٹی اتنی کہ بمشکل ایک صف ہی
بنتی ہے.اب لوگوں نے صلاح و مشورہ سے یہ طے کیا ہے کہ یا تو اس مسجد کو ہی پکا بنایا جائے
یا پھر باہر دوسری جگہ پر بڑی مسجد بنائی جائے.اب سوال یہ ہے
کہ آیا مسجدکی یہ جگہ کسی اور کام میں
لائی جا سکتی ہے یا نہیں ؟
ه : المغنی لابن قدامه باب الوقف مثه جلده که المغنی لابن قدامه من اهم الاحوال الشخصية على المذاهب الخمر من :
Page 229
ہوا ہے :.یہ خیال درست نہیں کہ جس جگہ ایک دفعہ مسجد بن جائے اس جگہ کو پھر کبھی بھی خواہ کیسے ہی
حالات در پیش ہوں کسی اور غرض کے لئے استعمال نہیں کیا جا سکتا.اصل خرابی جھلی کو روکنا مقصود
ہے وہ یہ ہے کہ اس قسم کے بہانے سے ایسی جگہ کے غلط استعمال کا راستہ نہ کھلے.یالوگوں کی
مرضی کے خلاف کارروائی کرنے کی کوئی صورت پیدا نہ ہو.اگر کوئی جائنہ وجہ موجود ہے مثلاً جگہ تنگ
ہے اور وسیع جگہ میں مسجد تعمیر کرنے کی ضرورت ہے اور اس مسجد سے تعلق رکھنے والے
لوگ اس تبدیلی پر راضی ہیں اور مرکز سے اس تبدیلی کی اجازت حاصل کرلی گئی ہے اور فتنہ
کے اُٹھنے کا کوئی موقعہ ممکن نہیں تو ایسی تبدیلی شرعًا جائز ہے اور پہلی مسجد کی جگہ کو حسب
حالات کسی اور قومی یا انفرادی مصرف میں لایا جا سکتا ہے.سوال :.موجودہ احمدیہ مسجد حاضری کے لحاظ سے ناکافی ہے اس کے اردگرد غیر احدی آباد ہیں کیا ہم یہ
مسجد غیر احمدیوں کو مفت دیدیں یا ان سے کچھ رقم وصول
کر کے نئی مسجد میں خرچ کریں یا اس
مسجد کو مبلغ کے لئے رہائشی کوارٹر میں تبدیل کر دیں اور اپنے لئے نئی مسجد بنائیں ؟
جواب :.مقامی جماعت کی رضا مندی اور مرکز کی اجازت سے یہ مسجد دوسرے عام مسلمانوں کے
حوالے کر سکتے ہیں.بہتر ہے کہ بلا معاوضہ دی جائے ہاں اگر وہ از خود احمدیوں کی زیر تعمیر مسجد
میں مدد کرنا چاہیں تو ایسی امداد لینے میں کوئی حرج نہیں.مسجد کا ایک حصہ مکان میں ملانا
ایک شخص نے مکان کے ایک حصہ کو مسجد بنایا اور اب اس کی ضرورت نہیں رہی.تو کیب
اس جگہ کو مکان میں ملایا جا سکتا ہے؟
حضرت اقدس نے فرمایا : ہاں ملالیا جاو سے لے
سوال: مسجد کا ایک حصہ اس طرح سے الگ کرنا جائز ہے کہ اس میں عورتیں مخصوص ایام میں
بھی آسکیں اور اس حقہ میں اپنا اجلاس کر سکیں ؟
جوا ہے :.اگر تو شروع تعمیر سے ہی یہ صورت ہے تو پھر جائز ہے لیکن اگر پہلے سارے حصے بطور
مسجد استعمال ہوتے اور مسجد محسوب ہوتے تھے اور بعد میں یہ صورت کی گئی ہے تو خلیفہ
وقت کی خاص اجازت کے بغیر ایسی تبدیلی جائزہ نہیں.: الحكم ار اکتوبر شراء
Page 230
۲۲۴
مسجد اور رہائشی کوارٹر
وال: مسجد کے صحن کے ایک حصہ میں امام الصلوۃ کے لئے بالاخانہ کے طور پر کوارٹر بنانا جائز ہے؟
جواب : اگر ضرورت واضح ہو اور اس کے بغیر مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہو تو مسجد کے صحن کے ایک حصہ
کے اوپر امام کے لئے بالاخانہ کی طرز کار ہائشی کوارٹر بنانا جائزہ ہے بشر طیکہ کوارٹر میں آنے جانے کا
راستہ مسجد کے صحن میں سے نہ گزرے.اسی طرح اس کا پر نالہ وغیرہ بھی دوسری طرف ہو.چنانچہ اس بارہ میں فقہائے حنفیہ کی یہ
رائے بیان کی گئی ہے.لَوْ بَنَى فَوْقَهُ رَبِّي فَوْقَ الْمَسْجِدِ بَيْنَا لِلإِمَامِ لَا يَضُرُّ لِاَنَّهُ
مِنَ الْمَصَالِح.اسی طرح مصدا یہ میں ہے :-
عَنْ أَبِى يُوْسُفَ أَنَّهُ جَوَدَ بِنَاءَ الْبَيْتِ) فِي الْوَجْهَيْنِ رَى فَوْقَ
الْمَسْجِدِ وَتَحْتَهُ حِيْنَ قَدِمَ الْبَغْدَادَ وَرَاى ضِيقَ الْمَنَازِلِ
نكانة إعتبر الضَّرُورَة وَمَنْ مُحَمَّدٍ حِينَ دَخَلَ الرَّيْ جَازَ
ذلك كله لما قلنا - ته
سوال : کیا مساجد کو بے حرمتی سے بچانے کے لئے گرا دینا جائز ہے ؟
جوا ہے :.اگر ایسے حالات موجود ہوں کہ کسی جگہ کو آباد نہ رکھا جا سکتا ہو مثلاً مسلمان اس جگہ کو کسی وجہ
سے چھوڑ آئے ہوں اور مسجد ویران ہو گئی ہو یا اس بات کا خدشہ ہو کہ عدم نگرانی و حفاظت
کی وجہ سے غیر مسلم مسجد کی بے حرمتی کریں گے تو ایسی صورت میں مرکز یا مقامی جماعت کے
مشورہ سے مسجد کو مسمار کیا جا سکتا ہے اور اس کا ملبہ دوسری مساجد کی تعمیر کے لئے استعمال
ہوسکتا ہے.نیز یہ بھی جائزہ ہے کہ اس علہ کو فروخت کر کے اس کی رقم دوسری آباد مسجد کے
مصارف میں خورج کی جائے.علماء نے مسجد یا دوسری وقف جائیدادوں میں اس قسم کے تصرف سے صرف اس لئے منع
کیا ہے کہ تا اس طرح کہیں مسجد کے اموال میں نا جائزہ تصرف کی راہ نہ کھل جائے.لیکن اگر یہ وجہ نہ
ہو بلکہ ضرورت اور مجبوری واضح ہو اور مقامی جماعت کی درخواست پر مرکز اس کی اجازت دے تو
ه باشيد و المختار ما هدایت اولین کتابه الوقت له مطبوعہ مطبع مجیدی کانپور ۱۳۲
Page 231
۲۲۵
اس قسم کی تبدیلی میں کوئی امر شرعی روک نہیں.و
فقہائے امت نے ایسی تبدیلی کے بارہ میں جس خدشہ کا اظہار کیا ہے اس کی بنیادی
وجہ وہی ہے جو اوپر بیان کی گئی ہے کہ اس طرح کی اجازت سے متولی یا دوسرے کسی متغلب
کے لئے ناجائز تصرف کا راستہ نہ کھل جائے.چنانچہ حنفیوں کی مشہور کتاب بحر الرائق شرح
کنز الدقائق میں ہے.نُقِلَ عَنِ الشَّيْحَ الاِمَامِ العُلُونِي فِي الْمَسْجِدِ وَالْحَوْضِ إِذَا خَرِبَ
لا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ لِتَفَرقِ النَّاسِ عَنْهُ إِنَّهُ تُصْرَفُ أَوْقَافُهُ إِلَى
مَسْجِدٍ آخَرَ وَحَوْنٍ آخَر - ل
في القِنْيَةِ أوْهَرِبَ اَحَدُ الْمَسْجِدَيْنِ فِي تَرْيَةٍ وَاحِدَةٍ
فَلِلْقَاضِي صَرْفُ خَشَبِهِ إِلَى عِمَارَةِ الْمَسْجِدِ الْآخَرِ - "
قَالَ مُحَمَّدٌ ذَا خَرِبَ وَلَيْسَ لَهُ مَا يُعْمَرُ بِهِ وَقَدِ اسْتَغْنَى النَّاسُ
عَنْهُ لِبِنَاء مَسْجِدٍ آخَرَ أو لِخَرْبِ الْقَرْيَةِ أَوَلَمْ يَخْرَبُ وَلَكِن
خَرِبَتِ الْقَرْيَةَ بِنَقْلِ اَهْلِهَا وَاسْتَغْنَوْاعَتْهُ فَإِنَّهُ يَعُودُ إِلَى
مِلْكِ الْوَاقِفِ أَوْ وَرِثْتِهِ -
سوال: کچھ مسجد کے بالے کیا فروخت کئے جاسکتے ہیں یا دریا میں ڈال دینا چاہیں یا دفن کر دیا
چاہئیں؟
جو اہے.مسجد کا قیمتی طیبہ دریا میں ڈالنا یا دفن کرنا اسلامی ہدایت کے مطابق درست نہیں اسے دوسری
مساجد کے مقاصد میں استعمال کیا جا سکتا ہے اور مقامی مجلس عاملہ کے فیصلہ اور مرکز کی منظوری
سے اسے فروخت کر کے اس کی قیمت اغراض مسجد میں صرف کی جا سکتی ہے اس میں کوئی
شرعی روک نہیں.سے
سوال : مسجد میں قریبا یکصد انیٹ پختہ ہے کسی کو یہ اینٹیں اس شرط پر دی جاسکتی ہیں کہ جب مسجد کا
کام شروع ہو گا تو اینٹیس یا قیمت دے دے گا ؟
: بحر الرائق كتاب الوقف فصل في احكام المساجد ص : : - بحر الرائق : ه: - بحر الرائق :
ه : - بحر الرائق كتاب الوقف فصل في احكام المساجد ص :
☑>
Page 232
جواب : مسجد چونکہ وقف ہے اور مقامی جماعت بصورت متولی اس کی نگران ہے اس لئے اس میں
ہر ضروری تصرف کے لئے مقامی جماعت باہمی مشورہ کے ساتھ مسجد کی عمارت کی بہتری کیلئے
کوئی مناسب فیصلہ کر سکتی ہے.اگر تعمیر کے لئے پختہ اینٹیں پڑی ہوئی ہوں لیکن تعمیر شروع ہونے میں دیر ہو اوران اینٹوں
کے ضائع چلے جانے کا خدشہ ہو اور ان کو بیچ دینے یا کسی کو ارمضانہ دے دینے میں مسجد کا
فائدہ ہو تو ند کورہ اصول کے مطابق ان اینٹوں کو بیچا جا سکتا ہے اور یہ بھی جائز ہے کہ یہ
اینٹیں اس شرط پر کسی دوسرے دوست کو دے دی جائیں کہ تعمیر شروع ہونے پر وہ اینٹیں
خرید کر مسجد کو واپس کر دے گا.کسی مسجد کے لئے چندہ
سوال :.ہم ایک مسجد بنانا چاہتے ہیں اور تبرکا آپ سے بھی چندہ چاہتے ہیں ؟
جوا ہے :- حضرت اقدس نے فرمایا :."ہم تو دے سکتے ہیں اور یہ کچھ بڑی بات نہیں مگر جبکہ خود ہمارے
ہاں بڑے بڑے اہم اور ضروری سلسلے خرچ کے موجود ہیں جن کے مقابل میں اس قسم کے خرچوں
میں شامل ہونا اسراف معلوم ہوتا ہے تو ہم کس طرح سے شامل ہوں.یہاں تو مسجد خدا بنا رہا ہے
اور وہی مسجد اقصی ہے وہ سب سے مقدم ہے.اب لوگوں کو چاہیے کہ اس کے واسطے روپیہ
بھیج کر تو اب میں شامل ہوں.ہمارا دوست وہ ہے جو ہماری بات کو مانے نہ وہ کہ جو اپنی بات کو
مقدم رکھتے.حضرت امام ابو حنیفہ کے پاس ایک شخص آیا کہ ہم ایک مسجد بنانے لگے ہیں آپ بھی اس میں
کچھ چندہ دیں.انہوں نے عذر کیا کہ میں اس میں کچھ نہیں دے سکتا حلانکہ وہ چاہتے توبہت کچھ
دیتے.اس شخص نے کہا کہ ہم آپ سے بہت نہیں مانگتے صرف تبر کا کچھ دے دیجئے.آخر انہوں نے
ایک دو آنے کے قریب سکہ دیا.شام کے وقت وہ شخص دوا نے لے کر واپس آیا اور کہنے لگاکہ مصر
یہ تو کھوٹے نکلے ہیں وہ بہت ہی خوش ہوئے اور فرمایا خوب ہوا.دراصل میرا جی نہیں چاہتا تھا.کہ
میں کچھ دوں.مسجدیں بہت ہیں اور مجھے اس میں اسراف معلوم ہوتا ہے " اے
سوال ہے.کیا احمدی تعمیر مسجد کے لئے دوسرے مسلمانوں یا غیرمسلموں سے چندہ لے سکتے ہیں ؟
ہوا ہے :.اپنے آپ کو خواہ مخواہ دوسروں سے مانگنے والوں میں شامل نہیں کرنا چاہیئے اپنی کوشش سے
14.1
ے: الحكم ۲۳ می شد
Page 233
ضرورت کے مطابق مسجد بنائی جائے.نیز مسجد کا شاندار ہونا یا ضرورت سے بڑی عمارت کا ہونا.یا
پختہ ہونا ضروری نہیں.بہر حال اپنے پر بھروسہ کرنے کی عادت ڈالنی چاہیئے تاہم ضرورت اور مجبوری
کے حالات کے لحاظ سے مندرجہ ذیل حوالے جوانہ کی سند بن سکتے ہیں :.I " 19 محترم منشی فرزند علی خانصاحب سلسلہ عالیہ احمدیہ میں داخل ہوئے.آپ
نے ایک مقامی رئیس منشی کرم الہی صاحب کو جن کی ایک مسجد ویران پڑی رہتی تھی تحریک
کی کہ وہ اپنی مسجد جماعت احمدیہ کو عنایت کر دیں.چنانچہ حسب ذیل چھٹی ان
کو بھجوائی
گئی.آپ کے والد صاحب مرحوم کی مسجد کی غیر آباد حالت دیکھ کر مجھے آپ
کی خدمت میں اس درخواست کے پیش کرنے کی جرأت ہوئی ہے کہ آپ فیروزپور
کی جماعت احمدیہ کو اس مسجد کے آباد کرنے کی اجازت فرما دیں :
اس کا جواب اس رئیس کی طرف سے یہ ملا کہ چونکہ یہ مسجد میرے بزرگوار کی تعمیر
کروائی ہوئی ہے اور میں تا اس دم اس کا متولی ہوں.میں بڑی خوشی سے آپ کو
اجازت دیتا ہوں کہ آپ کے ہم خیال لوگ اس میں نمانہ پڑھیں اور اس کو آباد کریں.اور شکست کی مرمت کروائیں.میری طرف سے اور دیگر مسلمانوں کی طرف سے آپ
کو کہ یہخہ
کو کوئی تکلیف نہ ہوگی.بیکن بہت خوش ہوں کہ یہ خانہ خُدا آباد ہو.یہ چند سطور بطور
اجازت نامہ لکھ دیتا ہوں تاکہ سند رہے.والسلام
جب اس کا رروائی کی اطلاع مرکز میں پہنچی تو الحکم جلد نمبر ۲۴ میں یہ نوٹ شائع ہوا
دو
منشی فرزند علی صاحب ایک قابل اور ہونہار نوجوان ہیں انجمن حمایت اسلام
کے لئے آپ نے بہت بڑا کام کیا ہے.سلسلہ عالیہ احمدیہ میں ابھی تھوڑے عرصہ
سے داخل ہوئے ہیں اور آپ کی سعی اور ہمت کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالٰی نے جماعت
احمدیہ فیروز پور کو ایک مسجد خطا بد کردی اے
I ایک صاحب نے عرض کیا کہ کیا گردوارے کی اینٹیں مسجد کی تعمیر میں استعمال کی جاسکتی
ہیں جبکہ سکھوں نے ایسا کرنے کی اجازت دے دی ہے ؟
فرمایا.اگر سکھوں نے اجازت دے دی ہے تو بے شک یہ اینٹیں مسجد میں استعمال
کی جا سکتی ہیں لیکن اگر انہوں نے اجازت نہ دی ہو تو پھر انہیں استعمال نہیں کیا جا
سکتا کیونکہ کسی چیز کو بغیر اس کے مالکوں کی اعجاز کے استعمال کرنا اسلام میں منع ہے یا کے
Sigur
: - الفصل ۲۸ جوائی سفر بن
:- الفصل یکم جنوری یہ لاہور ہے
Page 234
۲۲۸
سوال: کیا ز کوۃ کی رقم سے مسجد بنوائی جا سکتی ہے ؟
وا
جوا ہے :.بہتر تو یہی ہے کہ زکوۃ کی رقم مسجد کی تعمیر و مرمت پر خرچ نہ کی جائے.تاہم
زکواۃ افراد کے علاوہ ایسے مفید اداروں
کو بھی دی جاسکتی ہے جو کہ پبلک کے فائدہ
کے لئے ہوں اور عام پبلک ان سے فائدہ اٹھا سکتی ہو.یا خاص گردہ پبلک کا جو کہ
انفرادی طور پر زکواۃ کا مستحق ہے فائدہ اُٹھا سکتا ہو جیسے یتیم خانے.غریب خانے
مساجد - ہسپتال.کنویں.تالاب وغیرہ.چنانچہ بعض فقہاء نے فی سبیل اللہ سے
یہ استدلال کیا ہے کہ افراد کے علاوہ اداروں پر بھی یہ رقم خرچ کی جا سکتی ہے.لے
سوال : کیا قربانی کی کھالوں کی رقم مسجد کی ضروریات پر خرچ ہو سکتی ہے ؟
بہتر ہے کہ قربانی کی کھالوں کی قیمت غرباء کو دی جائے یا جیسا کہ انتظام ہے مرکز میں بھجوا
جواب :
دی جائے.اپنے طور پر بلا اجازت مرکز مسجد کی ضروریات پر یہ رقم خرچ کرنا مناسب نہیں.اور
یوں بھی یہ وقار مسجد کے خلاف ہے کہ ایسے صدقات کا مال جس سے مستحق غرباء میں مسجد کی تعمیر میں
خرچ کیا جائے.سوال : کیا فاحشہ عورت کی کمائی سے بنائی ہوئی مسجد میں نماز پڑھنا جائز ہے ؟
جوا ہے :- جو مسجد بن گئی ہے اور معاشرہ میں بطور مسجد اس کا مقام مان لیا گیا ہے اس میں نماز پڑھنا
جائز ہے.نماز پڑھنے والے کے لئے اس بات کی چھان بین کرنے کی ضرورت نہیں کہ یہ مسجد کر نے
بنائی ہے.کیسے پیسوں سے بنی ہے.رہا اپنا خیال تو جس کا جی نہیں چاہتا وہ نہ پڑھے.شریعت
تو صرف جواز سے بحث کرتی ہے.- 1
جو درخت کسی قبرستان میں لگے ہوئے ہیں ان کو فروخت کر کے کیا اس کی رقم کسی مسجد میں لگانا
درست ہے ؟
جواب :- عام قبرستان کی زمین اور اُس میں اُگے ہوئے درخت وغیرہ وقف کے حکم میں ہیں اگر گاؤں
والوں کی اکثریت اتفاق رائے سے ایسی آمدن کو مسجد کی اصلاح وغیرہ میں لگائے تو اس میں
شرعا کوئی امر مانع نہیں اور ایسا کرنا جائز ہے.گاؤں والوں کا اتفاق اس لئے ضروری ہے تاکہ فتنہ
پیدا نہ ہو.جو شخص صاحب اختیار اور مختار کا ر ہے وہ ایسے درختوں کو بیچ کر اُسے مسجد کی
مرمت وغیرہ میں صرف کر سکتا ہے صحیح حدیث میں ہے کہ ہجرت کے بعد مدینہ میں آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے جہاں اپنی مسجد بنوائی اور اب جو مسجد نبوی کہلاتی ہے وہاں ایک قبیلہ کا پرانا قبرستان
:- رساله تشريح الدكواة هنا :
Page 235
۲۲۹
تھا.آپ نے وہ جگہ اس کے مالکوں سے خرید کی اور اس میں جو کھجوریں وغیرہ تھیں انہیں مجید
کی چھت وغیرہ میں استعمال فرمایا.چنانچہ حدیث کے الفاظ ہیں :-
من اني أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يُصَلِّي حَيْتُ
أَدْرَكَهُ الصَّلوةُ وَيُصَلِّيَ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَانَّهُ أَمَرَ بِجَنَاءِ
الْمَسْجِدِ فَاَرْسَلَ إِلَى مَلَاء بَنِي التَّجَارِ فَقَالَ يَا بَنِي النَّجَارِ تَا ضُنِي
بِحَائِطِكُمْ هَذَا قَالُوا لاَ وَاللهِ لَا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلَّا إِلَى اللَّهِ عَزَّوَ
جَل قَالَ انَ وَكَانَ فِيْهِ مَا أَقُولُ لَكُمْ تُبُورَ الْمُشْرِكِينَ لِه
اس روایت سے ظاہر ہے کہ قبرستان کے درختوں کو مسجد میں استعمال کرنا منع نہیں.مسجد کی زینت
دہلی کی جامع مسجد کو دیکھ کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا.کہ مسجدوں کی اصل زینت
عمارتوں کے ساتھ نہیں ہے بلکہ ان نمازیوں کے ساتھ ہوتی ہے جو اخلاص کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں.یہ
سب مساجد ویران پڑی ہوئی ہیں.مسجد کی رونق نمازیوں کے ساتھ ہے مسجدوں کے واسطے حکم ہے کہ
تقویٰ کے واسطے بنائی جاویں کیے
سوال :.مسجد کے محراب پر نقش ونگار یا شعر وغیرہ لکھا جا سکتا ہے ؟
جواب : مساجد خصوصا قبلہ والی دیوار اور محراب میں نقش و نگار، تحریر، استعاره و آیات وغیرہ کو پسند
نہیں کیا گیا.اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ اس طرح نمازی کی توجہ بنتی ہے اور وہ یکسوئی سے نماز
نہیں پڑھ سکتا.(1)
است
سلسلہ میں چند احادیث جن سے استدلال کیا گیا ہے درج ذیل ہیں :
عَنِ ابْنِ عَبَّاسَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أُمِرْتُ
اللهِ
بتَشْبِيْدِ الْمَسَاجِدِ - قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَتُزَ خَرِ فَنَّهَا كَمَا نَ خَرَفَتِ
اليَهُودُ وَالنَّصَارَى
ه بخاری کتاب الصلوة - باب هل ينبش قبور مشركي الجاهلية الخصلت : ه: - فتاد فی احمدیه ص
سه : - البو داؤد كتاب الصلاة باب فى بناء المسجد ص :
Page 236
۲۳۰
یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا.مجھے بلند اور عالیشان مساجد بنا نے کا حکم نہیں دیا گیا.حضرت ابن عباس نے اس کی تشریح یہ کرتے ہیں کہ یہود و نصاری کی طرح بلند و بالا عالیشان عبادتگا ہیں
بنانا ان کی تزئین کرنا اوران میں سیم سیم کے نقش و نگار بنانا اور سونے سے انہیں ملی کرنا بعثت
رسول کے مقاصد میں شامل نہیں.رسول تو سادہ زندگی کی تلقین کے لئے آتے ہیں.۲، عَنْ أَنيَّ أَنَّ النَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ
حَتَّى يَتَبَاحَى النَّاسُ فِي الْمَسَاجِدِه
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی ایک علامت یہ ہے کہ لوگ عالی شان مساجد
بنانے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے اور انہیں باہمی تفاخر کا ذریعہ قرار دینے کی
کوشش کریں گے.(۳) عَنْ عُثْمَانَ بْنِ طَلْحَةَ انَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَاهُ بَعْدَ
دَخُولِهِ الكَعْبَةَ فَقَالَ إِنِّي كُنتُ رَأَيْتُ تَرْلَى الْكَبْشِ حِينَ دَخَلْتُ
الْبَيْتَ فَنَسِييْتُ اَنْ امْرَكَ اَنْ تُخَمِّرَهُمَا فَخَمِرُهُمَا فَإِنَّهُ لَا
يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فِي قِبْلَةِ الْبَيْتِ شَيْءٍ يُلْقِي الْمُصَلَى - له
یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبہ میں داخل ہوئے تو کلید بردار کعبہ حضرت عثمان بن طلحرف
کو بلایا اور فرمایا.جب میں خانہ کعبہ کے اندر آنے لگا تھا تو میں نے مینڈھے کے سینگ دیوانہ
کعبہ پر نصب دیکھے تھے.تم انہیں ڈھانک دو.کیونکہ قبلہ کی جہت کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیئے
جو نمازی کی توجہ کو ہٹا دے.سوال :- مسجدوں کے اندر قرآنی آیات کے قطعات آویزاں کرنے میں کوئی حرج ہے؟
جو ا ہے :.اصل ہدایت یہ ہے کہ حتی الوسع نمازی کے سامنے دیوار یا کسی اور چیز پر ایسے نقش و نگار.قطعات و آیات وغیرہ نہیں ہونی چاہئیں جو اس
کی توجہ کو ہٹا دیں اور اُس کی یکسوئی میں حارج ہوں
البتہ کچھ بلندی پر جو نظر کے سامنے کے خط مستقیم سے
اوپر ہو تبلیغی اغراض کے ماتحت آیات ،
احادیث یا اشعار لکھنے یا قطعات لٹکانے میں بظاہر کچھ ہرج نہیں.ه: ابن ماجد كتاب الصلوۃ باب تشييد المساجد من و ابوداود کتاب الصلوة باب في بناء المساجد صدا
ت : - ابو داؤد كتاب المناسك باب الصلوة في الكعبة ص ، مسند احمد ص :
Page 237
۲۳۱
سوال ہے :.کیا مسجد کی دیوار پر اندریا با ہر ایسے لوگوں کے نام کندہ ہو سکتے ہیں جنہوں نے نمایاں
چندہ دے کہ تعمیر مسجد میں حصہ لیا ہو اور ان سے چندہ لیتے وقت نام لکھنے کا وعدہ بھی کیا گیا ہو؟
جواب : - اصولاً مساجد کے اصلی حصہ کو سادہ اور یادگاری کتبات وغیرہ سے پاک رکھنا چاہیئے تاہم اس
میں ایسی سختی بھی نہیں.کیونکہ بعد کے خلفاء اور بزرگوں نے اس کی بعض صورتوں
کو جائزہ رکھا ہے سب
سے بہتر اور انسب صورت یہ ہے کہ
مسجد میں اگر کسی خاص تاریخی اہمیت کا کتبہ لگانا ہو تو تفصیل لکھ کر خلیفہ وقت یا ان کی
طرف سے کسی مجانہ ادارہ سے پہلے اجازت حاصل کی جائے.(۳) حتی الوسع کتبہ مسجد کے باہر کے حصہ میں رجس میں مسجد کا برآمدہ اور صحن شامل نہیں لگایا
جائے.مثلاً مسجد میں داخلے والے بڑے دروازے کے پاس یا چار دیواری کے کسی
مناسب حصہ ہیں.یہ امر بہر حال پیش نظر رہنا چاہیئے کہ نمازیوں کے بالکل سامنے والی دیوار میں جس پر زمانہ
پڑھتے ہوئے نظر پڑ سکتی ہے ایسے کتبات جو توجہ کو ہٹانے والے ہوں نہ لگائے جائیں.مسجد اور مدرسہ
سوال :.ہمارے یہاں مساجد میں پرائمری کلا میں لگتی ہیں مسجد میں میز کرسی لگا دی جاتی ہیں.لڑکے
اور استاذ جوتا پہن کر مسجد میں آتے جاتے ہیں.نمازہ کے وقت صفیں اور دریاں بچھا دی جاتی ہیں.جوا ہے.مساجد میں تعلیم و تدریسی جائزہ ہے لیکن بالکل مدرسہ کے طور پر اس کا استعمال درست نہیں
کیونکہ مساجد کا ادب و احترام اس امر کا مقتضی ہے کہ انہیں صاف ستھرا رکھا جائے اور گندہ
ہونے سے بچایا جائے.یا پھر ایسی جگہوں کا نام مسجد نہ رکھا جائے.جہاں نمازہ کے علاوہ اس
رنگ میں تدریس و تنظیم کا کام بھی ہوتا ہو اور اس کے لئے میز کرسی یاڈیسک استعمال کرتے
پڑتے ہیں اور جوتیوں سمیت اندر باہر آنے جانے میں کوئی روک ٹوک نہ ہو بہتر ہے کہ ایسی جگہوں
کا نام مدرسہ رکھدیا جائے اور عارضی طور پر اسے نماز پڑھنے کا کام بھی لے لیا جائے.نماز کے وقت
صفیں اور دریاں بچھادی جائیں.بہر حال ایک جگہ کو مسجد قرار دینے اور اس کا نام مسجد رکھنے کے بعد آداب مسجد کو ملحوظ
رکھنا ضروری ہے.
Page 238
۲۳۲
مسجد اور اس میں سستانے کی اجازتے
سوال : گرمیوں میں ایک شخص مسجد میں ظہر کی نماز پڑھنے کے لئے آتا ہے اور مسجد میں نماز عصر تک رہتا
ہے.کیا اس عرصہ میں وہ مسجد میں سو سکتا ہے ؟
جوا ہے.مسجد کو خوابگاہ کے طور پر استعمال نہ کیا جائے.یہ صدایت و ارشاد اس مقصد کے لئے ہے کہ
مسجد کو نا واجب باتوں اور غیر ضروری استعمال سے محفوظ رکھا جائے تاکہ عبادت اور ذکر الہی میں
حرج نہ ہو.تاہم وقت ضرورت مسجد میں انسان آرام کے لئے لیٹ سکتا ہے اور سوبھی سکتا ہے
نہ بطور حق کے بلکہ صرف ضرورت اور مجبوری کے پیش نظر
سوال: کیا گم شدہ اشیاء کا اعلان مسجد میں ہو سکتا ہے؟
جواب : مسجد کے اندر گئی ہوئی چیز کا اعلان با جازت امیر پریذیڈنٹ یا امام مسجد کے اندر ہو سکتا ہے.جو چیز باہر گئی ہو یا لاپتہ ہوئی ہو اس کا اعلان مسجد سے باہر ہونا چاہیے.اسی طرح ایسے امر کے متعلق
جس کا تعلق جماعت کے انتظام سے ہو یا کسی شرعی مسئلہ ہے ، اس کا اعلان بھی مسجد میں کیا
جا سکتا ہے لیے
سوال : کیا نماز کی جگہ تھوکنا اور ادھر ادھر کی باتیں کرنا جائز ہے ؟
جو اہے :- جہاں نماز پڑھی جائے اس جگہ کو ہر قسم کے گند سے اور لغو امور سے پاک رکھنا چاہیئے میسجد
میں لغو باتیں کرنا اور شور مچانا بھی جائز نہیں.ایک دفعہ صاحبزادہ میاں بشیر احمد صاحب اپنے دوسرے بھائیوں کے ساتھ کھیلتے کھیلتے
مسجد میں آگئے اور اپنے ابا جان حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پاس ہو بیٹھے.وہ اپنے لڑکپن
کے باعث کسی بات کے یاد آجانے پر دبی آواز سے بار بار کھل کھلا کر ہنس پڑتے تھے.اس پر حضرت
اقدس علیہ السّلام نے فرمایا کہ مسجد میں ہنسنا نہیں چاہیے " سے
سوال:.گرمیوں کے موسم میں جب مسجد کا صحن سخت گرم ہو جاتا ہے تو صحن عبور کر کے آنے میں نمازیوں کو
سخت تکلیف ہوتی ہے.اگر صحن میں ٹاٹ بچھا دیا جائے تو کیا جوتے پہنے ہوئے مسجد میں داخل ہو سکتے ہیں؟
له : ابوداؤد كتاب الصلوة ياب في كراهية انشاء الضالة في المسجد من ، ابن ماجه باب النهي عن
انشاد الطوال في المسجدمة :
ته: فتاوی احمدیہ صل :
Page 239
۳۳۳
جواب: اگر جوتی صاف ہو اور اس کے تلوے پر گند لگا ہوا نہ ہو تو اسے پہنے ہوئے انسان مسجد میں
جاسکتا ہے.ٹاٹ بچھا ہوا ہو تو یہ اور زیادہ بہتر صورت ہوگی.تاہم چونکہ یہاں یہ طریق معروف
کے مطابق نہیں اور لوگ ایسا کرنے کو برا مناتے ہیں اس لئے فتنہ اور جھگڑے سے بچنے کے
لئے اس
سے اجتناب اوئی ہے تا کہ فتنہ پردازی اور الزام تراشی کا سی کو کوئی موقع نہ مل سکے.سوال : کیا جوتا پہن کر نماز پڑھی جا سکتی ہے ؟
جواہے :.صاف جوتے پہن کر نماز پڑھنا جائز ہے.یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے
تاہم فتنہ اور فساد سے بچنے کے لئے ایسا کرنے سے اجتناب کیا جائے.جہاں تک جواز کا تعلق
ہے اس کے لئے بعض حوالہ جات درج ذیل ہیں :-
، عَن سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ قُلْتُ لَا نَسَ بْنِ مَالِكِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ قَالَ نَعَمْ.اس حدیث پر محاکمہ کرتے ہوئے حضرت امام ترمدی لکھتے ہیں :
حَدِيثُ رَنَسٍ حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيمٌ وَالْعَمَلُ على هذا عندا هل
العلمية
(۲) عَنْ شَدَادِ نِ ارْسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالِفُوا
اليهود فإنَّهُمْ لا يُصَلُّونَ فِي نِعَالِهِمْ وَلَا خِفَانِهِمْ.٣.(۳) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى
في التقلين.(م) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ مَنْ جَدِهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلّى حَافِيًا وَمُتَنَقِلاً.(۵) عن عبد الله قال لقدر اينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى في.النعلين والخفين - شه
سید نا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں ذکر ہوا کہ امیر کابل اجمیر کی خانقاہ میں
مسلم كتاب الصلواة باب جواز الصلاة في التخلين ها ، بخاری باب ما جاء في الصلوة في التعال من له ترندي كتاب الصلوة بالصلوة
:.في الفعال ها بود او د باب الصلوة في النحل : : : - ابن ماجہ کتاب الصلواة باب الصلوة في التعال منت :
Page 240
۲۲۴
بوٹ پہنے چلا گیا اور ہر جگہ بوٹ پہنے ہوئے نماز پڑھی.اور اس بات کو خانقاہ کے مجاوروں
نے بُرا منایا.حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا.کہ اس معاملہ میں امیر حق پر تھا.جوتے پہنے
ہوئے نما نہ پڑھنا شرعاً جائز ہے.بے
الے بند کی میٹنگ مسجد میں ہوتی ہے.کیا حائضہ عورت مسجد کے اندر منعقد ہونے والی سیٹنگ
میں شامل ہو سکتی ہیں ؟
جوا ہے.اگر مجبوری کی حالت ہو مثلاً اجلاس کے لئے کوئی اور موزوں جگہ ہی نہ ہو تو پھر حائضہ عورت کا
مسجد میں جانا جائز ہے کیونکہ ممانعت کی اصل وجہ خالص تعبدی یعنی محض عبادت کے لئے نہیں
بلکہ قومیت مساجد یعنی خون کے گرنے کے امکان کی وجہ سے مساجد کے گندہ ہو جانے کا خدشہ ہے.لیکن موجودہ زمانہ میں عورتیں جس قدر اس بارہ میں احتیاط کرتی ہیں اس کے پیش نظر ایسے خدشات
کا کوئی موقع نہیں ہے اس لئے بحالتِ ضرورت و مجبوری اس کی اجازت دی جاسکتی ہے.اس
لچک کا استدلال مندرجہ ذیل روایت سے کیا جا سکتا ہے :-
إِنَّ مَيْمُونَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ
رَأسَهُ فِي حُجْرِ إِحْدَانَا فَيَتْلُوا الْقُرْآنَ وَهِيَ حَائِضُ وَتَقَومُ
إحْدَانَا بِخَمْرَتِهِ إِلَى الْمَسْجِدِ فَتَبَسُطُهَا وَهِيَ حَائِمَ - لَ
ال: حائضہ کے مسجد میں داخل ہونے کے بارہ میں حنفیہ کے علاوہ دوسرے مذاہب کا کیا مسلک
جوا : حائضہ عورت ضرورت کے وقت مسجد میں داخل ہو سکتی ہے یا نہیں اس بارہ میں حنفیوں
کا
مسلک یہ ہے کہ وہ مسجد میں نہیں جا سکتی.ان کے مسلک کی تائید میں صرف یہ حدیث ہے جو
افلت" نامی ایک راوی سے ابو داؤد نے روایت کی ہے :-
بوتِ صحابه
شَارِعَةٌ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ وَجهُوا هذه البُيُوتَ عَنِ الْمَسْجِدِ
تُم دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَلَمْ يَدْمَعِ الْقَوْمُ شَيْئاً
رِجَاءَ أَن تَنْزِلَ فِيهِمْ رُخْصَةٌ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ بَعْدُ فَقَالَ
وَجَدُوا هَذِهِ الْبُيُوتَ عَنِ الْمَسْجِدِ فَانّي لَا أُحِلَّ الْمَسْجِدَ
ه بدر در ایریل نگاه : ۲۲ : - نسائی کتاب المساجد ص :
Page 241
لِحَائِضِ وَلَا جُنب"
(۱) اس حدیث کی صحت کے متعلق علامہ ابن رشد اپنی مشہور کتاب بداية المجتھد میں
لکھتے ہیں :.ما روى عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَام اَنَّهُ قَالَ لَا أُحِلَّ الْمَسْجِدَ لِجُنُبِ وَلَا
حَائِضِ وَهُوَ حَدِيثُ غَيْرُ ثَابِتٍ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ : له
۲۱ ، علامہ ابن حرم اس مسئلہ اور اس حدیث کے بارہ میں لکھتے ہیں :-
لَمْ يَثْبُتُ فِي هَذَا الْبَابِ شَيْءٌ وَحَدِيثُ أَفَلَتَ بَاطِلُ " کے
(۳) صحابہ میں سے حضرت زید بن ثابت اور بعد کے علماء میں سے امام ابو داؤد ظاہری اور ان
کے متبعین اس بات کے قائل ہیں کہ حائضہ عورت بوقت ضرورت مسجد میں جا سکتی ہے اور جس
حدیث میں ممانعت آئی ہے اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ مسجد تلویث اور گندہ ہونے سے محفوظ
رہے.اگر اس قسم کا کوئی اندیشہ نہ ہو تو پھر حائضہ عورت کا مسجد میں جانا منع نہیں.کے
ابن مندر کی روایت ہے کہ :-
دو كَانَ اَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشُونَ فِي
الْمَسْجِدِ وَهُمْ جُنب -
وال: - قبر کے بالمقابل نماز پڑھنی جائز ہے یا نہیں ؟
جواب: مزار یعنی قبر کو جانتے ہوئے اس کے بالمقابل نماز نہیں پڑھنی چاہیئے.خواہ اس کے خیال میں
اس مزار اور قبر کی تعظیم نہ بھی ہو.نے
مسجد اور تنازعہ
سوال ہے :.لوگ مل کر ایک مسجد بناتے ہیں پھر ان میں سے کچھ لوگ احمدی ہو جاتے ہیں جنہیں غیر احمدی
وہاں نماز پڑھنے سے روکتے ہیں.کیا احمدی وہاں نماز پڑھنے سے رک جائیں ؟
له : ابوداؤد کتاب الطہارت ج : له: بداية المجتهد ما :
ه : - بذل المجهود شرح ابو داؤد من :- نیل الاوطار باب الرخصة في اجتياز الجنب في المسجد
ومنعه من الليث فيه الا ان يتوضأ : نیل الاوطار باب الضا : : : : - الفضل ا ) :
Page 242
جواب : " یہ تو سوال ہی غلط ہے.اصل بات یہ ہے کہ ایسے معاملات میں حالات پر غور کر لینا چاہیے.اگر
وہ احمدی سمجھتے ہیں کہ بغیر فساد کے وہ اپنا حق لے سکتے ہیں تو انہیں اپنا حق لے لینا چاہیئے.اور
اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس جھگڑے میں لمبا وقت صرف ہوگا تو مومن کا کام یہ ہے کہ جتنا وقت اس کا
مقدمہ پر خرچ ہو سکتا ہے اتنا وقت تبلیغ پر خرچ کرنے اور مقدمہ بازی نہ کرنے " ہے
تعظیم قبله
سوال :.قبلہ شریف کی طرف پاؤں کر کے سونا جائز ہے یا نہیں ؟
جوا ہے : سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوة والسلام نے فرمایا.یہ ناجائز ہے.کیونکہ تعظیم کے
بر خلاف ہے.سوال : - احادیث میں اس کی ممانعت نہیں آئی ؟
فرمایا : یہ کوئی دلیل نہیں ہے اگر کوئی شخص اس بنا پر کہ حدیث میں ذکر نہیں ہے اور اس لئے
قرآن شریف پر پاؤں رکھ کر کھڑا ہوا کہ سے تو کیا یہ جائز ہو جاوے گا.ہرگز نہیں.وَمَنْ تُعْظِمْ
شَعَائِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ لَه
سوال : کیا قبلہ کی طرف مجبوری سے بھی پاؤں کرنا منع ہے ؟
جواہے :.قبلہ کی طرف پاؤں کرنا کفر تو نہیں البتہ ادب کے خلاف ہے.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
پیشاب وغیرہ کے متعلق فرمایا ہے اگر آگے دیوار نہ ہو تو ادھر منہ کر کے پیشاب نہیں کرنا چاہیئے مگر
دوسری جگہ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ آپ کو ایسا کرتے دیکھا گیا.اس کی یہی تشریح کی گئی ہے کہ سامنے
دیوار تھی.قبلہ کی طرف پاؤں نہ کرنا ادب کاطریق ہے لیکن اگر کوئی کریگا تو بد تہذیب ہے کہ ہے
سوال : کعبہ کی طرف پاؤں کر کے نہ سونے کی شرعی حجت کیا ہے ؟
جوا ہے.کعبہ کی طرف پاؤں کر کے سونے کو بزرگوں نے خلاف ادب سمجھا ہے اس لئے اس سے بچنا چاہیے."
سوائے اس کے کہ کوئی خاص عذر ہو.مثلاً بیمار کے لئے ادائیگی نمازہ کی یہ صورت علماء نے لکھی ہے کہ
اگر انسان بوجہ بیماری لیٹ کر نماز پڑھنے پر مجبور ہو تو چت لیٹ کر نماز پڑھے.پاؤں کعبہ کی طرف
ہوں اور سر مقابل کی سمت میں نے
١٩٧٠
له الفضل، رمى له سه سورة الحج : ۳۳ : سه : بدر ۲۴ جودائی سماعت الحکم ، دراگ یه ی
فتاوی مسیح موعود ص :: له الفضل ۲۹ جون شاء : كشف الغمه باب صلوة المعذور
Page 243
abit
اسی طرح حدیث میں اس بات کی تصریح آئی ہے کہ کعبہ کی طرف منہ یا پیٹھ کر کے پیشاب
یا پاخانہ کے لئے نہیں بیٹھنا چاہیئے.حدیث کے الفاظ یہ ہیں :-
عَنْ إِلَى أَيُّوبَ الأَنْصَارِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ إِذَا الَى أَحَدُكُمُ الغَائِطَ فَلَا يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَلَا
يُوَتِيْهَا ظَهْرَهُ شَرِكُوا أَدْغَرِبُوا - لها
بخاری کتاب الصلوة باب لا تستقبل القبلة الغائط اوبول الاعند البنساء جدار أو نحوه صدا
۲۶
Page 244
نماز جنازه
جب بتقاضائے قدرت کسی کی وفات کا وقت قریب آجائے تو اس کے پاس سورہ یسین پڑھی
جائے لیے دیے دیے اور بلند آواز سے کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت بھی پڑھنا چاہیئے.وفات واقعہ ہو جانے
پر اور ایسی خبر طنے پر موجود لوگ إِنَّا لِلهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعون پڑھیں.مرنے والے کی آنکھوں کو
ہاتھ سے بند کر دیں.سر کو باندھ دیں تاکہ منہ کھلا نہ رہ جائے.جزع و فزع کی بجائے صبر اور حوصلہ کے
سنا" متعلقین تجہیز و تکفین کا اہتمام کریں.میت کو غسل دیں اس کا طریق یہ ہے کہ تین بار بدن پر تازہ یا نیم گرم پانی ڈالیں اگر ہو سکے تو پانی
میں بیری کے پتے ملانا مسنون ہے.پہلے وہ اعضاء دھوئے جائیں جو وضوء میں دھوئے جاتے ہیں.کلی کرانے اور ناک میں پانی ڈالنے یا پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں.اس کے بعد بدن کے دائیں اور
بائیں حصہ پر پانی ڈال کر دھوئیں.نہلاتے وقت بدن کے واجب الستر حصہ پر کپڑا پڑا رہنا چاہیئے.مردمیت کو مرد اور عورت قیمت کو عورت نہلائے.بشرط ضرورت بیوی اپنے متوفی میاں کو نہلا سکتی
ہے.اسی طرح مرد اپنی بیوی کو نہلا سکتا ہے لیے
نہلانے کے بعد کفن پہنایا جائے جس میں کم قیمت اور سادہ سفید کپڑا استعمال کیا جائے.مرد کے
تین کپڑے.گرتہ ، تہہ بند اور بڑی چادر جیسے لفافہ بھی کہتے ہیں اور عورت کے لئے ان تین کپڑوں کے علاوہ
سینہ بند اور سربند بھی ہونے چاہئیں.تجہیز و تکفین میں سادگی اختیار کرنا موجب برکت و ثواب ہے.شہید کو نہلانے اور کفن پہنانے کی ضرورت نہیں.اُسے اپنے پہنے ہوئے کپڑوں میں ہی دفنایا جائے.غسل اور تکفین کے بعد میت کا منہ دیکھنے کی اجازت ہے.سے
هاب (الف) ابن ماجہ ابواب الجنائز باب ما يقال عند المريض اذا حضر منها :
(ب) ابو داؤد کتاب الجنائز باب القرأة عند الحميت مي :
له : - (الف) ابن ماجد ابواب الجنائز باب في غسل الرجل امراته وغسل المراة زوجها مثنا :
رب دار قطنی ، بیہقی ص ۳۹ جلد ۳ - كتاب الحلية ابو نعيم في ترجمته فاطمة :
: - ابن ماجہ ابواب الجنائز باب ماجاء في النظر الى الميت اذا اورج في القائد ملت في
Page 245
۲۳۹
تکفین کے بعد جنازہ کو کندھوں پر اٹھا کر جنازہ گاہ سے جایا جائے.وہاں نماز جنازہ کے لئے
حاضر لوگ امام کے پیچھے صف باندھیں.زیادہ لوگ ہوں تو صفیں طاق بنائی جائیں لیے امام صفوں کے
آگے درمیان میں کھڑا ہو.بیت اس کے سامنے ہو.امام بلند آواز سے تکبیر تحریمہ کہے.مقتدی بھی
آہستہ آہستہ آواز میں تکبیر کہیں.اس کے بعد ثناء اور سورہ فاتحہ آہستہ آواز سے پڑھی جائے پھر
امام بغیر ہاتھ اٹھائے بلند آواز سے دوسری تکبیر کہے اور مقتدی بھی آہستہ آواز سے کہیں.پھر
درود شریف جو نماز میں پڑھتے ہیں پڑھا جائے.پھر تیسری تکبیر کہی جائے اور میت کیلئے مسنون
دھا کی جائے.اس کے بعد چوتھی تکبیر کہ کہ امام دائیں بائیں بلند آواز سے السلام علیکم ورحمتہ اللہ کہے
اور مقتدی آہستہ آواز سے یہ سلام کہیں سے
بوقت ضرورت کسی غیر معمولی شخصیت کی نماز جنازہ غائب بھی پڑھی جاسکتی ہے.اسی طرح جس
کا جنازہ کسی نے نہ پڑھا ہویا بہت تھوڑے سے آدمی جنازہ میں شریک ہو سکے ہوں تو اس کی نما نہ جیت اندہ
غائب پڑھنا بھی جائز ہے بشرطیکہ مقامی جماعت جنازہ غائب پڑھنے کا فیصلہ دے یا مرکزہ سے اس کی
اجازت حاصل کر لی جائے کہ
نماز جنازہ فرض کفایہ ہے.یعنی سب مسلمانوں پر بحیثیت مجموعی فرض ہے.اگر کچھ لوگ نماز پڑھ
لیں تو باقی میکدوش ہو جائیں گے لیکن با وجود علم ہو جانے کے اگر کوئی نہ پڑھے توسب گنہگار ہوں گے.نماز جنازہ کی مسنون دعائیں
بالغ مرد اور بالغ عورت کے لئے دُعا : -
(1) هُمَّ اغْفِرْ لِعَيْنَا وَمَيتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيرِنَا وَ
كَبِيرِنَا وَذَكَرِنَا وَاُنْثَنَاء اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَاحْيِهِ
عَلَى الْإِسْلَامِ وَ مَن تَوَنَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَقَهُ عَلَى الْإِيْمَانِ وَاللهُمَّ
لا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تَفَتِنَا بَعْدَة - ثم
اه :- ابن ماجہ کتاب الجنائز باب ماجاء في من صلى عليه جماعة من السلمين منا ب شه : عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه
وسلم قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب بخاری مرفوعا ها ، ترندی ها ، ابن ماجه ها ، ابوداؤ ر م :
تحفة الفضاء منه : له : و - بخاری باب الصلوة على القبر من - ب نطالب ابر احاديث الصلوة على الغائب جناب
: - ابن ماجہ کتاب الجنائز باب في الدعاء في صلاة الجنازة مكنا :
Page 246
یعنی اسے اللہ بخش دے ہمارے زندوں کو اور جو مر چکے ہیں اور جو حاضر ہیں اور ہو
موجود نہیں.اور ہمارے چھوٹے بچوں کو اور ہمارے بڑوں کو اور ہمارے مردوں کو اور
ہماری عورتوں کو اسے اللہ جس کو تو ہم میں سے زندہ رکھے اُسے اسلام پر قائم رکھ اور
جس کو تو وفات دے اس کو ایمان کے ساتھ وفات دے.اسے اللہ اس کے اجر و
ثواب سے ہم کو محروم نہ رکھا اور اس کے بعد ہمیں کسی فتنہ میں نہ ڈال.م - اللهُمَّ اغْفِرْلَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَاكْرِمَ مُنْزَلَهُ وَوَسِعْ
مدخَلَهُ وَاغْسِلَهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلِهِ وَالْبَرَدِ وَنَقَةٍ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا.ينقى الثوب الأبيضُ مِنَ الدَّنَسِ وَابْدَلَهُ دَارً ا خَيْرًا مِنْ دَارِه.وأهلا خيرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ
وَاعِدُهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَ مِنْ عَذَابِ النَّارِط - له
یعنی اسے اللہ اس کو بخش دے اور اس پر رحم فرما اور اس کو معاف کردے اور
اس سے درگزر فرما اور اس کو عزت کی جگہ دے اور اس کے داخل ہونے کی جگہ کو کشادر
فرما اور فصل رہے اس کو پانی اور برف سے اور اولوں سے یعنی تپیش گناہ آپ رحمت کے
ذریعہ اس سے دُور کر دے.اور پاک وصاف کہ اس کو خطاؤں سے جیسا کہ سفید کپڑا ئیل
کچیل سے ڈھل کہ صاف ہوتا ہے اور اس کو اس کے گھر کے بدلہ میں اچھا گھر عطاء فرما اور
اچھے اہل دے اس کے اہل سے اور اچھے ساتھی اس کے ساتھی سے.اور اس کو بہشت
میں داخل فرما اور اس کو قبر کے عذاب اور آگ کے عذاب سے محفوظ رکھنے
- نابالغ لڑکے کے جنازہ کی دُعا : -
اللهُمَّ اجْعَلَهُ لَنَا سَلَفَا وَنَرَفًا وَ ذُخْرًا وَ اَجْرًا وَشَانِمَا وَ مُشَفَعًات
یعنی اسے اللہ اس کو ہمارے فائدہ کے لئے پہلے جانے والا اور ہمارے آرام کا
ذریعہ بنا اور سامان خیر بنا اور موجب ثواب یہ ہما را سفارشی بنے اور اس کی سفارش قبول فرما.1- اگر عورت کی میت ہو تو مذکر کی غیر کی بجائے موت کی ضمیر استعمال کی جائے مثلا اللهُمَّ اغْفِرْ لَهُ کی جگہ اللهُم
اغْفِرْ لَهَا وَارْحَمْهَا الله : نسائی کتاب الجنائز باب الدعا ص ، ابن ماجد كتاب الجنائز باب الدغما في الصلوة
على الجنازه مثنا :
بخاری کتاب الجنائز فيها ، شرح السنه ص ۳۵ :
Page 247
۲۴۱
تم - نابالغہ لڑکی کے جنازہ کی دعاء :-
اللَّهُمَّ اجْعَلَهَا لَنَا سَلَفَا وَنَرَطَا وَ ذُخْرًا وَاجْرًا وَشَافِعَةٌ وَمُشَفَعَةٌ.یعنی.اسے اللہ اس بچی کو ہمارے فائدہ کے لئے پہلے جانے والی اور ہمار سے آرام کا
ذریعہ بنا اور سامان خیر بنا اور موجب ثواب یہ ہماری سفارشی بنے اور اس کی سفارش
قبول فرما.نماز جنازہ کے بعد جتنی جلدی ہوسکے میت کو دفنانے کے لئے قبرستان لے جایا جائے.سب
ساتھ جانے والوں کو باری بازی کندھا دینے کی کوشش کرنی چاہیے.اگر میت بھاری ہو یا اُسے دور لے
جانا ہو تو گاڑی یا ٹرک وغیرہ پر رکھ کر لے جایا جا سکتا ہے.جنازہ لے جاتے وقت ساتھ ساتھ زیر لب
ذکر الہی اور دعائے مغفرت بھی کرتے جانا چاہیئے.قبر لحد والا یا شق دار دونوں طرح جائز ہے.البتہ میت کی حفاظت کے پیش نظر کشادہ اور گہری
ہونی چاہیے.بصورت مجبوری ایک قبر میں کئی منتیں بھی دفن کی جاسکتی ہیں.اگر میت کو امانتاً دفن کرنا ہو
یا زمین سخت سیلا بہ ہو تو میت کی حفاظت کے مد نظر لکڑی یا لوہے کے صندوق میں دفن کر سکتے ہیں یہ
چنانچہ صاحب رو المختار رکھتے ہیں :-
ر ولا بأس باتخاذ تابوت) ولو بحجر او حديد وله عند الحاجة) كرخاوة
الأرض
میت کو احتیاط کے ساتھ قبرمیں اتارتے وقت بِسْمِ اللَّهِ عَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ صلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّم کے الفاظ کہے جائیں.اور لپٹی ہوئی چادر کا بند کھول کہ میت کا منہ ذرا قبلہ کی طرف
جھکا دیا جائے.کچھ اینٹیں یا چوڑے پتھر رکھ کر لحد بند کر دی جائے اور اوپر مٹی ڈال دی جائے.بہر حاضر
کو مٹی ڈالنے میں کچھ نہ کچھ حصہ لینا چاہیئے اور نہیں تو دونوں ہاتھوں سے تین سٹھی مٹی ڈالے اور ساتھ یہ
آیہ کریمہ پڑھے :-
مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيْهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى - له
قبر کو مسطح اور تھوڑی سی کو ہان دار بنانا مسنون ہے.قرتیار ہونے پر مختصری دعائے مغفرت کی جائے
: ردّ المختارص جلد اول حاشیه سه: ابن ماجہ کتاب الجنائز باب ماجاء في ادخال الميت
القبر ما : ه: - سوره طه : ۵۷ ، بیہقی مواد نیل الاوطار باب من ابن يدخل الميت قبره...الخ حيث :
Page 248
۲۳۲
اس کے بعد السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَإِنَّا إِنْشَاء الله
بِكُمْ لاحِقُونَ نَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَة - کہتے ہوئے بادلِ حزیں وصبر و حوصلہ واپس
آئیں لیے
میت کے عزیزوں کے ساتھ تعزیت کی جائے اور صبر و حوصلہ کی تلقین کی جائے.قریبی یا پروسی
پسماندگان کے گھر ایک وقت کا کھانا بھی بھجوائیں.رسوم پرستی اور تو ہمات سے اجتناب کیا جائے.افسوس اور تعزیت کی حالت تین دن تک قائم رکھی جائے.اس کے بعد زندگی معمول پر آجانی چاہیئے.البتہ جس عورت کا خاوند مر جائے وہ چار ماہ دس دن تک سوگ منائے.یعنی بلا اشد ضرورت
گھر سے باہر نہ نکلے.بناؤ سنگار نہ کرے.بھڑکیلے کپڑے نہ پہنے.خوشبو کا استعمال نہ کرے.خوشی کی تقریبات میں شامل نہ ہو اور صبر و شکر کے ساتھ ذکر الہی میں یہ دن گزار ہے :
ه: ابن ماجد كتاب الجنائز باب فيما يقال اذا دخل المقابر ملك ؟
Page 249
۲۴۳
متفرقات
مرض کی صورت میں صحیح علاج کی طرف زیادہ توجہ دی جائے.نیز شافی مطلق کے حضور صحت
کے لئے درد و الحاج کے ساتھ دُعا کی جائے.صدقہ دیا جائے.دعا کی ایک صورت دم بھی ہے اور اس رنگ میں کسی بزرگ سے بطور تبرک دم کہ انا جائز
ہے لیکن نہ تو اس طریق کو عام کیا جائے اور نہ ہی اسے بطور پیشہ اختیار کیا جائے.آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کا عموما یہی طریق تھا اور آپ کے صحابہ کا بھی یہی عمل رہا کہ دعا کے اس طریق کو بہت کم
اختیار کیا گیا.کیونکہ اس میں بدعت کے راہ پانے اور رسم چل پڑنے کا بھی ڈر ہے.عام طور پر سورہ فاتحہ اور معوذتین پڑھ کر دم کرنے کے بارہ میں روایات آئی ہیں.سوال :- مریض کو قرآن مجید کی کونسی آیات پڑھ کر دم کیا جائے ؟
جوا ہے :.بخاری کی یہ روایت اس بارہ میں ہماری رہنمائی کرتی ہے :-
عنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا
آوى إِلَى فِرَاشِهِ نَفَثَ فِي كَفَّيْهِ بِقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ وَ
بِالْمُعَوَّذَ تَيْنِ جَمِيعًا ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ وَمَا بَلَغَتْ
يَدَاهُ مِنْ جَسَدِهِ قَالَتْ عَائِشَةُ نَلَمَّا اشْتَكَى كَانَ يَأْمُرُني
ان افعل ذلِكَ بِه له
یعنی.حضرت عائشہ یہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام جب سونے کے لئے بستر پر لیٹتے
تو اپنے دست مبارک پر سورہ اخلاص سورہ فلق اور سورہ الناس پڑھ کر پھونک مارتے اور
پھر ہاتھوں کو چہرہ اور تمام جسم پر جہاں تک ہاتھ پہنچتا پھیر تے اور جب آپ بیمار ہوتے
تو مجھے ایسا کر نے کے لئے فرماتے.حضرت خلیفہ اسیح الثانی نے اس قسم کے ایک سوال کے جواب میں فرمایا : -
ردم مریض پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ عقلاً
اس کا فائدہ اور اس کی حکمت معلوم ہوتی ہے.باقی چیزوں پر دم.....رسول اللہ
۵۵
بخاری کتاب الطب باب النفث في الرقية ص: ه: - بخارى كتاب الطب باب النفث في المرقية م :
Page 250
صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں....گو اس میں بھی بعض حالات میں فائدہ ہو سکتا ہے
مگر اس سے بعض نتائج پیدا ہو سکتے ہیں جو خطرناک ہیں.ان کا فائدہ کم ہے اور نقصان
زیادہ ہے.یہ روحانیت پر ایسا اثر ڈال دیتی ہے کہ خُدا تعالیٰ سے دور کر دیتی ہے یہ
چیزیں انسان کو دُعا سے غافل کر دینے والی ہیں اور خُدا کی طرف بار بار رجوع کرنا جو ایمان
کی جزو ہے اس سے انسان کو دور کر دیتی ہے " اے
سوال :.وفات کے وقت مسلمان کے لئے کونسی دعا پڑھی جاتی ہے ؟
جواب : - جب ایک مسلمان پر حالت نزع طاری ہو تو پاس والے کلمات خیر کہیں.مثلاً
(الف) لا إِلَهَ إِلَّا اللہ پڑھیں.لہ
(ب) خوش الحانی سے حاضرین میں سے کوئی سورہ یاسین کی تلاوت کری سے.سے
رج ، نیز یہ ذکر کرنے کا بھی حکم ہے :-
إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون - اللَّهُمَّ أَجِرْنِي فِي مُصِيبَتِي.مجھے
وَاخْلُفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا - له
سوال: - اگر کوئی بصورت ایسی حالت میں مر جائے کہ وہاں کوئی دوسری صورت نہیں یا مرد مر جائے جبکہ
کوئی دوسرا مرد وہاں نہیں تو پھر غسل اور نماز جنازہ وغیرہ کسی طرح ہوگا.جواب : - میدان جنگ میں اگر کوئی عورت ماری جائے تو بلا غسل اس کی تجہیز و تکفین کی جائے.ہاں نمازہ
جنازہ میں اگر کوئی روک نہ ہو تو پڑھی جائے.بحالت ضرورت غیر محرم مرد عورت کا جنازہ اُٹھا
سکتے ہیں.اور اس کی تدفین بھی کر سکتے ہیں.اگر کوئی عورت میدان جنگ میں قتل نہ ہو بلکہ کسی مرض کے
وفات ہو تو غسل کے لئے کپڑوں سمیت اُوپر پانی ڈالا جائے اور پھر کفن میں لپیٹ کر تدفین کی
جائے.بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ اس صورت میں بلاغسل تدفین ہو یا میت کو تسیم کر دیا جائے.یعنی اس کی باہوں
اور منہ پر ہاتھ پھیر جائے اور اس وقت تیم کرانے والا اپنے ہاتھوں پر
کپڑا لپیٹ ہے.نے
الفضل ۲۶ فروری ۴۹۲۳ : ۵۲ ترندی ملا ، ابوداؤد باب فی التلقین مت : ٣ : ابو داؤد کتاب الجنائز باب
القراءة عند البيت م: له اسلم باب ما يقال عند المصيبة ناشی - مراسیل ابو داود باب غسل المیت او.امصری
:
Page 251
۲۴۵
ہمارے نزدیک میشت کے رشتہ دار یا جماعت کے ذمہ دار عہدہ دار حسب صوابدید و موقع
مناسب فیصلہ کر سکتے ہیں جس طرح بیماری کی صورت میں اگر لیڈی ڈاکٹر نہ ملے تو عورت مرد
ڈاکٹر سے بھی علاج اور قابل ستر حصہ میں بیماری کی تشخیص کر سکتی ہے.اسی طرح یہاں بھی یہ
طرز عمل اختیار کیا جا سکتا ہے.بہر حال یہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے اور پردہ اور غیر محرم کو چھونے کی ممانعت سے متعلق
مام ہدایات پر اس اجتہاد کی بنیاد ہے.فقہاء نے اس سلسلہ میں جو کچھ لکھا ہے اس کا
خلاصہ یہ ہے :-
انْفَقُوا عَلَى أَنَّ الرِّجَالَ يَغْسِلُونَ الرِّجَالَ - وَالنِّسَاءَ يَفْسِلُنَ
النِّسَاء وَاخْتَلَفُوا فِي الْمَرأَة تَمُوتُ مَعَ الرِّجَالِ أَوِ الرَّجُلُ
يَمُوتُ مَعَ النِّسَاء مَا لَمْ يَكُونَا زَوْجَيْنِ عَلَى ثَلَاثَةِ اقْوَالٍ فَقَالَ
قَوْم يَغْسِلُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ مِنْ فَوْقِ الشَّيَابِ
وَقَالَ قَوْمُ يَتَيَمَّمُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ وَبِهِ قَالَ
الشَّافِعِى وَالوَحَنِيفَةَ وَجَمْهُورُ الْعُلَمَاءِ وَقَالَ قَوْمُ لا يَغْسِلُ
كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ وَلَا يَتَيَمَّمُهُ وَقَالَ كَيْتُ مِن سَعْدٍ
بَلْ يُدُ فَنُ مِنْ غَيْرِ غُسْلٍ هِ
غسل میت طاعون زده
سوال : - طاعون زدہ کے غسل کے واسطے کیا حکم ہے ؟
ہوا ہے :.فرمایا " مؤمن طاعون سے مرتا ہے تو وہ شہید ہے.شہید کے واسطے غسل کی ضرورت نہیں تھ
طاعون زدہ کو کفن
سوال :- طاعون زدہ کو کفن پہنایا جا وے یا نہیں ؟
جوا ہے :.فرمایا " شہید کے واسطے کفن کی ضرورت نہیں.وہ انہیں کپڑوں میں دفن کیا جائے.ہاں
اس پر ایک چادر ڈال دی جائے تو ہرج نہیں ہے " سے
سوال :.خواتین کے کفن میں کتنے کپڑے ہوتے ہیں سُنا ہے آجکل ایک پاجامہ کا اضافہ ہوا ہے؟
ل بداية المجتهد الباب الثاني في غسل الميت الفصل الثالث : ه: - بدرم را پریل عنه :
Page 252
۲۴۶
جوا ہے :.کفن کے طور پر عورت کے لئے ضرورت کے لحاظ سے پانچ کپڑے تفصیل ذیل ہونے چاہئیں
تهر بند ، گرتا ، لفافہ ، سینہ بند ، مانی جیسے سر کے بال باندھے جائیں.یہ مسنون تعداد ہے.اس سے
زیادہ کپڑے کفن میں استعمال کرنا بدعت کا رنگ اختیار کر سکتا ہے.اس سے بچنا چاہیے.کفن سفید معمولی قیمت کے لٹھے یا کھدر کا ہونا چاہیئے.سوالے :.جنازہ اٹھاتے وقت نیت کا سر کس طرف ہونا چاہیے ؟
جوا ہے : - جنازہ کو قبرستان لے جانا اور اس کی تدفین میں حصہ لینا ایک شرعی ہدایت ہے اور شرعی
ہدایت کی بنیاد قرآن کریم اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر ہے.ہم اپنے قیاس یا خود
ساختہ حکمت سے کسی امر یا طریق کار کو شرعی قرارہ نہیں دے سکتے.اس اصول کو مد نظر ر کھتے
ہوئے جنازہ کو اٹھانے کے بارہ میں جو ہدایت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے ملتی
ہے وہ یہ ہے کہ میت کو چارپائی یا اسی شکل کی کسی اور چیز مثلاً سٹریچر وغیرہ پر لٹانا چاہیئے.حدیث
میں اس کے لئے سریر کا لفظ آیا ہے پھر اس جنازہ کو چار آدمی اٹھائیں البتہ اگر مشکل ہو یا عذر ہو تو دو
آدمی بھی اُٹھا سکتے ہیں.اس طرح بوقت ضرورت سواری کے کسی جانور.گاڑی چھپکڑے.ایمبولینس کار وغیرہ پر بھی جنازہ کو قبرستان کی طرف سے جا سکتے ہیں.-
احادیث میں ایسی کوئی تشریح نہیں ملتی جس بالوضاحت یہ پتہ چل سکے کہ جنازہ لے جاتے
وقت میت کا سرکیس طرف اور پاؤں کس طرف ہونے چاہئیں.تاہم طبعی طریق جسے سنت ، عمل
اور امت کے تعامل نے واضح کیا ہے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے خلفاء نے
عملاً اس کی تصدیق فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ میت کا سراد ہر ہونا چاہیئے جدہ جنازہ لے جایا جارہا
ہے اور حکمت دینی کا تقاضہ بھی یہی ہے.فقہ کی کتابوں میں جنازہ اٹھانے کا جو طریق لکھا ہے وہ یہ ہے :-
تُحْمَلُ الْجَنَازَةِ مِنْ جَوَانِبِهَا الْأَرْبَعِ فَيَبْدَأُ الَّذِي يُرِيدُ هَمْلَهَا
"
بِالْمُقَدَّ مِ الأَيْمَنِ مِنَ الْمَيِّتِ فَيَجْعَلَهُ عَلَى عَاتِقِهِ الْاَيْمَن ثَ
المُورِ الايْمَن عَلَى مَا يَقِهِ الْأَيْمَنِ ثَمَّ الْمَقَدَّمِ الْأَيْسَرَ عَلَى
عَاتِقِهِ الْأَسْرِيةَ الْمُوَخَرِ الايْسَرِ عَلَى عَايق الانتر - لا
یعنی جنازہ چار اطراف سے اُٹھایا جائے.جو شخص جنازہ کو کندھا دینا چاہے وہ پہلے میت کے
اگلے حصہ کی دائیں جانب کو کندھا دے.پھر دوسرا اس کے پچھلے حصہ کی دائیں جانب کو کندھے پر
:- تحفة الفقهاء من :
Page 253
۲۴۷
رکھے.پھر تیسرا اگلے حصہ کی بائیں جانب کو کندھا دے اور چوتھا پچھلے حصہ کی بائیں جانب کو
کندھا دے.حضرت انس سے طبرانی کی روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-
مَنْ حَمَلَ جَوَابَ السَّدِيرِ الْأَرْبَعَ كَفَرَ
اللهُ عَنْهُ اَرْبَعِينَ كبيرة له
یعنی جو شخص جنازہ کو چاروں اطراف سے اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے چالیسں قصور
معاف کر دے گا.نماز جنازہ میں چار سے زیادہ تکبیریں
(1)
مسلم ترندی ابو داؤد کی حدیث ہے کہ :.كان زيْدُ بْنُ اَرْقَمَ يُكَبِّرُ عَلَى جَنَا يُزِنَا اَرْبَعًا وَإِنَّهُ كَبَّرَ خَمْسًا نَسَانَتُهُ
فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْبَرُهَا - له
یعنی.زید بن ارقم کرنے ایک جنازہ پڑھاتے ہوئے پانچ تکبیریں کہیں جب پوچھا گیا تو
انہوں نے بتایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی رکبھی کبھی اس طرح چار سے زائد تکبیریں.کہا کرتے تھے.عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنْ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ عَلَى أَهْلِ بَدْرِسِتَا وَعَلَى
الصَّحَابَةِ خَمْسًا وَ عَلَى سَائِرِ النَّاسِ أَرْبَعًا - له
ب : - عَنْ عَلَى أَنَّهُ كَبَرُ عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ سِنَا وَقَالَ إِنَّهُ شَهِدَ
بدرا له
یعنی.ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی بدری صحابہ کے جنازہ میں چھ دوسرے
صحابہ کے جنازہ میں پانچ اور عام لوگوں کے جنازہ میں چار تکبیریں کہا کرتے تھے.بخاری
میں بھی اسی مضمون کی حدیث آئی ہے کہ حضرت علی نے ایک بدری صحابی سہل بن حنیف کے
جنازہ پر چھ تکبیریں کہیں.طبرانی الاوسط بحوالہ نیل الاوطار كتاب الجنائز باب حمل الجنازة والسير بها مي: 1 الجودا و ابواب الجنائز باب التكبير على الجنازة ميناء
ابن منذر بحوالہ نیل الاوطار صنده به که: بخاری کتاب المغازی میاد و نصب الرايه مي ونیل الاوطار ص.
Page 254
۲۴۸
پس ان احادیث سے چار سے زائد تکبیرات کا جواز ثابت ہے.گو عام دستور چار
تکبیریں کہنے کا ہے.سوال : بمباری کی وجہ سے بہت سے فوجی ریزہ ریزہ ہو گئے ان کی نمازہ جنازہ اور قبر کے بارہ
میں کیا حکم ہے؟
ہوا ہے - ایک ہی جگہ نعشوں کے بچے ہوئے حصوں کو جمع کر کے اکٹھے جنازہ پڑھا جائے اور ایک قبر
میں دفن کر دیا جائے.اس میں کچھ حرج نہیں.احد کی جنگ میں ایک قرض کئی کئی شہدا کو دفن
کیا گیا تھا.ن الرجل والرجلان والقلقة في ثوب واحد لما يدفنون في
قَبْرٍ وَاحِدٍ - له
مشتبہ الحال
شخص کا جنازہ
مشتبہ الحال شخص سے مراد ایسا شخص ہے جو اگرچہ با قاعدہ طور پر تو جماعت احمدیہ میں داخل نہ ہو مگر
حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا مکذب بھی نہ ہو بلکہ احمدیوں سے میل جول رکھتا ہو اور حضرت مسیح موعود
علیہ السلام کی صداقت کے متعلق ان کی ہاں میں ہاں ملا کر ایک گونہ تصدیق کرتا ہو.ایسے شخص کے جنازہ
کے بارہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ظاہراً کوئی حرج نہیں سمجھا.اگر چہ انقطاع کو بہتر قرار دیا ہے.جماعت احمدیہ کا عمل ایسے شخص کے بارہ میں بھی حضور کے ارشاد کے آخری حصہ پر ہے یعنی انقطاع
کو بہر حال بہتر خیال کیا گیا ہے.مناسب حالات میں پہلے حصّے پر بھی عمل کرنے میں کچھ حرج نہیں رہیں
کی اجازت لی جاسکتی ہے بشرطیکہ امام احمدیوں میں سے ہو.اگر نماز جنازہ میں امام احمدی نہ ہو سکتا
ہو تو پھر ایسے شخص کے جنازہ کا بھی سوال پیدا نہیں ہوتا.اس سلسلہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا
مندرجہ ذیل خط ایک سند کی حیثیت رکھتا ہے یہ
ہ جو شخص صریح گالیاں دینے والا کافر کہنے والا اور سخت مکذب ہے اس کا جنازہ
تو کسی طرح درست نہیں.مگر جس شخص کا حال مشتبہ ہے اس کے لئے کچھ ظاہر حرج نہیں
ہے.کیونکہ جنازہ صرف دُعا ہے اور انقطاع بہر حال بہتر ہے " ۵۲
سوال : جو آدمی اس سلسلہ میں داخل نہیں اس کا جنازہ جائز ہے یا نہیں ؟
جواب : حضرت اقدس نے فرمایا : -
ه ترمذی باب قتل احد و ذکر حمزه صا
: ۲۳ فروری *
Page 255
۲۴۹
" اگر اس سلسلہ کا مخالف تھا اور ہمیں برا کہتا تھا اور بُرا سمجھتا تھا تو اس کا جنازہ نہ
پڑھو اور اگر خاموش تھا اور درمیانی حالت میں تھا تو اس کا جنازہ پڑھ لینا جائز ہے
بشر طیکہ نماز جنازہ کا امام تم میں سے ہو ورنہ کوئی ضرورت نہیں.متوفی اگر بالجہر
مکذب اور مکفر نہ ہو تو اس کا جنازہ پڑھ لینے میں کوئی حرج نہیں کیونکہ علام الغیوب
خُدا ہی کی ذات پاک ہے یا اے
غیر مبالع کا جنازہ
ایسے غیر مبائع جنہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانہ میں خدمت کی ہے.اگر اب انہوں
نے بہتک نہ کی ہو تو ہمارا فرض ہے کہ حضور کی طرف سے ان کی خدمت کا آخرمی بدلہ جنازہ پڑھ کر دیں.اس پر کئی لوگ مجھ پر ناراض بھی ہوئے مگر اس بارے میں میرا نفس اس قدر مطمئن ہے کہ میں کسی کی
ناراضگی کی پرواہ نہیں کرتا.میں سمجھتا ہوں ہمارے دل نبض سے پاک ہونے چاہئیں.زندگی میں ہم اُن
سے دلائل سے لڑیں گے لیکن ان کی وفات کے بعد خُدا تعالٰی سے یہی کہیں گے کہ یہ تیرے مسیح پر
ایمان لائے تھے ہمیں جو تکلیف ان سے پہنچی ہے وہ ہم معاف کرتے ہیں اور تیرے حضور اُن کے لئے
مغفرت کی درخواست کر تے ہیں.خواجہ کمال الدین صاحب کی وفات پر بھی میں نے ایسا کیا تھا.خلافت سے انکار تو اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھتا ہے مگر ان کی وفات کی خبر سنتے ہی میں نے اُن کے لئے
دعا کی اور کہا کہ میں اپنی تکلیف معاف کرتا ہوں اللہ تعالی کو بھی انہیں معاف کر دے ؟ ۲
بچوں کا جنازہ
حضرت خلیفہ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :-
احمدیوں کے بیچے احمدی ہیں اور جب تک کسی احمدی کا لڑکا یا لڑکی بلوغت کو پہنچ
کہ احمدیت کا انکار نہ کر سے وہ احمدی ہی سمجھا جائے گا.اور اسی احمدیوں کا ساہی معاملہ
ہوگا.کیونکہ اولا رجب تک ان میں سے کوئی بالغ ہو کہ باپ کے مذہب کی مخالفت کا
اعلان نہ کر سے باپ کے مذہب پر ہی شمار ہوگی بلکہ احمدی ماں کے بچے بھی احدی ہی
سمجھے جائیں گے خواہ باپ غیر احمدی ہی کیوں نہ ہو.پس ایسے تمام لڑکے لڑکیوں کا
جنازہ جائز ہے" سے
١٩٠٢ء
۱۹۱۸
ن الحکم اپریل تنشطه البدرهم نوبته لها الفضل بر جنوری مردم به تله الفضل دار اکتوبر شارة ۱۳۰ ،
و : ۱۵
Page 256
۲۵۰
سوال ہے :.پھانسی پانے والے شخص کی نماز جنازہ ؟
جوا ہے : جس شخص کو پھانسی کی سزامی ہو اس کی نماز جنازہ جائز ہے.امام احمدبن حنبل فرمایا کرتے تھے.مَا يُعْلَمُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكَ الصَّلوةَ عَلَى أَحَدٍ الْأَعْلَى
الْفَالِ وَقَاتِلِ نَفْسِه - له
یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم قومی امانت (غنائم میں خیانت کرنے والے اور
خود کشی کرنے والے کے سوا باقی سب کی نماز جنازہ پڑھ لیا کرتے تھے اور یہی عام علماء کا
ملک ہے.ایک عورت نے بدکاری کے جرم کا اعتراف
کیا اور اُسے اس جرم میں سزائی اور وہ
مر گئی کیسی نے اس عورت کے حق میں میرا بھلا کہا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا.اسے
برا نہیں کہنا چاہیے.اس نے اپنے جرم کا اعتراف کر کے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر کوئی بڑا ظالم
حاکم بھی کرہ سے تو اس کی بخشش ہو جائے.ایک اور روایت میں ہے کہ اعتراف جرم کی صورت
یں سزا پانا ایسی توبہ کا رنگ رکھتا ہے کہ گریہ تو یہ ایک بڑی قوم پرتقسیم کی جائے توان کی بھی
مغفرت ہو جائے.حدیث کے الفاظ ہیں :-
قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ تَابَ تَوْبَةٌ لَوْ قَمَتْ.بيْنَ أُمَّةٍ لَوَسِعَتْهُمْ - که
سوال : خودکشی کرنے وا سے کی نمازہ جنازہ ؟
جواب : - آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کشی کرنے والے کی نماز جنازہ نہیں پڑھی.چنانچہ حدیث
میں آتا ہے :-
إِنَّ رَجُلاً قَتَلَ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٣
ایک شخص نے تیز پھل والے تیر سے خود کشی کر لی تو آپ نے اس کی نمازہ جنازہ نہ پڑھی بعض
: - نیل الاوطار كتاب الجنائز باب الصلواة على من قتل في حد ص :
مسلم كتاب الحدود باب من اعترف على نفسه بالزلي من :
: ابن ماجه كتاب الجنائز باب في الصلاة على اهل القبلة ما :
Page 257
۲۵۱
علماء نے کہا ہے کہ آپ کا یہ عمل عبرت اور فعل کی شناعت کے اظہار کے لئے تھا کہ یہ بہت
ہی بدی کا کام ہے.اسی بناء پر حضرت امام ابو حنیفہ - حضرت امام مالک اور بعض دوسرے علماء
نے اجازت دی ہے کہ اگر عام لوگ ایسے شخص کی نماز جنازہ پڑھ لیں توکوئی شناعت نہیں لیے
تاہم ہماری جماعت اجتناب کو بہتر سمجھتی ہے.غیر
مسلم کی وفات اسلامی معاشرہ میں
اگر کوئی غیرمسلم کسی سلمان کے ہاں یا اسلامی معاشرہ میں فوت ہو جائے اور اس کے لواحقین کے
لئے اس
کی تجہیز و تکفین کا انتظام کرناممکن نہ ہو تو تکفین و تدفین کا انتظام مسلمان اپنے طریق پر کر سکتے
ہیں.البتہ غسل دینے کی ضرورت نہیں.تھ
جنازہ غائب
کسی عبادت کے جواز کے لئے شرعی سند کا نقد و ضروری نہیں اگر یہ ثابت ہو جائے کہ ایک بار بھی
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا کام کیا جس کا بنیادی تعلق دین و عبادت سے ہے.اور پھر
امام وقت نے اس سند کی بناء پر اس دینی کام کو رواج دیا اور اس میں ایک تسلسل اور با قاعدگی
کی طرح ڈالی تو یہ طرز عمل جوانہ و استحسان کے لئے اصول شرعیہ اور قواعد فقہیہ کے عین مطابق ہوگا.انش اصول کی بناء پر جماعت احمدیہ نما نہ جنازہ غائب کی قائل ہے.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
سے ثابت ہے کہ آپ نے نجاشی شاہ حبشہ (جو مسلمان ہو چکے تھے) کی نمازہ جنازہ پڑھی تھی جبکہ نجاشی
کی نعش ظاہری لحاظ سے عام دستور کے مطابق آپ کے سامنے نہ تھی.چنانچہ مسند احمد کی روایت
ہے :-
نَعِلَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّجَاشِي لِاَصْحَابِهِ ثُمَّ قَالَ
اسْتَغْفِرُ وا لَهُ ُثمَّ خَرَجَ بِاَصْحَابِهِ الْمُصَلَّى ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى بِهِمُ
كَمَا يُصَلَّى عَلَى الْجَنَازَةِ - -
ه : نیل الاوطا رباب ترک الامام الصلاة على الخال وقاتل نفسه صلح جلدم : ه: - (الف) ابو داؤد باب الرجل
٣ صـ
۵۲۹
يموت له قرابة مشرك صيها - (ب) جدايه : ١٥٣- مسند احمد :
Page 258
۲۵۲
حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو نجاشی کی وفات کی خبر سنائی.پھر فرمایا اس کے لئے
بخشش کی دعا کرو.پھر آپ اپنے صحابہ کے ساتھ جنازہ گاہ میں آئے اور کھڑے ہو کر
اس طرح نماز پڑھائی جس طرح رسامنے پڑے ہوئے) جنانہ سے کی نماز پڑھائی جاتی ہے.ترمذی نے بھی اسی مضمون کی روایت کی ہے.چنانچہ وہ لکھتے ہیں :-
عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
اِن اَخَاكُمُ النَّجَاشِي قَدْمات فَقُومُوا فَصَلُّوا عَلَيْهِ.ایک اور روایت ہے :-
عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَمْسَعْدِ مَانَتْ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّم فَائِبُ فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى عَلَيْهَا وَقَدْ مَعَنَى لِذَابِكَ شَهْراً - له
یعنی حضور علیہ السلام باہر تھے کہ ام سعد وفات پاگئیں.جب ایک ماہ کے بعد
آپ تشریف لائے اور آپ کو وفات کا علم ہوا تو آپ نے اس کی نمازہ جنازہ پڑھائی.مجموعہ احادیث کی مشہور کتاب کشف الغمہ میں ہے :-
كَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يُصَلَّى عَلَى الْغَائِبِ عَنِ الْبَلَدِ - من
کہ حضور علیہ السلام اس شخص کا جنازہ پڑھتے جو مدینہ سے دور کسی دوسری جگہ فوت ہوتا.غرض اس مضمون کی احادیث صحاح ستہ میں بکثرت آئی ہیں.اسی بناء پر صاحب نیل الاوطار
لکھتے ہیں :-
بذالِكَ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَاَحْمَدُ وَجَمْهُورُ السَّلْفِ حَتَّى قَالَ ابْنُ حَزْمٍ
لَم يَاتِ مَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ مَتْعَاءُ - قَالَ الشَّافِعِيُّ الصَّلَوةُ عَلَى
الْمَيِّتِ دُمَاء لَهُ فَكَيْفَ رَايُدعى لَهُ وَهِيَ غَائِبُ أَوْ فِي الْقَبْرِ - لله
یعنی فقہ کے مشہور عالم حضرت امام شافعی اور حضرت امام احمد بن حنبل اور اکثر
بزرگان سلف جنازہ غائب پڑھنے کے قائل تھے مشہور محدث ابن حزم کہتے ہیں کہ کسی
صحابی کے متعلق یہ نہیں آتا کہ اپنی جنازہ غائب سے منع کیا ہو.امام شافعی فرمایا کرتے
ه : ترمزی : ه :- ترمذی باب الصلاة على القبر ص : ه: - كشف العمر ص ۲۹
- نیل الاوطار الصلاة على الغائب بالنية و على القبر الى شهر :
Page 259
۲۵۳
تھے کہ نماز جنازہ تو ایک دُعا ہے پھر غائب میت کے لئے یہ دُعا کیوں جائز نہیں.حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا :-
ہے :-
(1)
جو جنازہ میں شامل نہ ہو سکیں وہ اپنے طور پر دعا کریں یا جنازہ غائب پڑھیں “ لے
•
اس سلسلہ میں جماعت احمدیہ کا بالعموم طرز عمل یہ ہے کہ مندرجہ ذیل صورتوں میں جنازہ فائب ستحسن
وفات پانے والی اہم شخصیت ہو اور مرکز سے جنازہ غائب کی تلقین کی گئی ہو.(۲) موقع پر جنازہ پڑھنے والا کوئی نہ ہو یا کسی وجہ سے بہت تھوڑے لوگ جنازہ میں شرکت کر سکے
(۳)
ہوں اور مقامی جماعت نے اس بناء پر بالاتفاق جنازہ غائب کا فیصلہ کیا ہو.امام وقت کسی خاص وجہ سے کسی مرحوم کی نماز جنازہ غائب پڑھنا مناسب خیال کریں یا اس کی
ہدایت دیں.نماز جنازہ کا تکرار
ایک میت کی کئی بار نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے اور اس کا جواز مندرجہ ذیل روایات سے
ثابت ہے :-
(۱) انَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى قَتْلَى أَحَدٍ عَشْرَةٌ وَفِي كُلِّ عَشْرَةً حَمْرَةٌ (١)
(۲)
حَتَّى صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعِينَ - لَ
حضرت امام اعظم کی چھ بار نماز جنازہ پڑھی گئی.سے
سوال :.نماز جنازہ حاضر یا غائب میں مردوں کے ساتھ عورتوں کی شمولیت کے بارہ میں کیا حکم ہے؟
جواب :.نماز جنازہ میں عورتوں کی شمولیت کے اہتمام کو پسند نہیں کیا گیا.یہی وجہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے زمانہ میں اور پھر اس زمانہ کے حکم و عدل کے عہد میں اس نماز
میں عورتوں کی شمولیت کی کوئی نمایاں مثال ہمیں نہیں ملتی.البتہ اگر اتفاقی طور پر کوئی عورت شامل
نماز ہو جائے.مثلاً جمعہ یا درس کے لئے عورتیں جمع ہیں اور جنازہ آگیا ہے یا گھر
کے صحن میں نماز
جنازہ ہو رہی ہے اور صفوں کے پیچھے دو چار عورتوں نے اپنی صف بنا کر نماز پڑھ لی ہے تو ایسی
له: - بدر وارمٹی من :- نیل الاوطار ترك الصلوة على الشهيد : مراسیل ابوداؤ دمش
ے
:- سیرت ائمہ اربعہ ص :
Page 260
۲۵۴
صورت جانہ ہوگی.اسی طرح نماز جنازہ غائب میں بصورت موجود گی دجیسے جمعہ کی نماز کے بعد جنازہ غائب یا حاضر
ہو اور عورتوں کو اپنی الگ صنف بنانے کے لئے مسجد سے باہر نہ جانا پڑے تو وہ نماز جنازہ میں شامل
ہو سکتی ہیں.اس کا جواز مندرجہ ذیل روایات سے نکلتا ہے اور سابقہ علماء نے بھی ان سے ایسا ہی
(1)
استدلال کیا ہے.عن أَبي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ انَّ عَائِشَةَ لَمَّا تُوَتِي سَعَدُ ابْن ابي
وَقاصِ قَالَتْ ادْخُلُوا بِهِ الْمَسْجِدَ حَتَّى أُصَلِّي عَلَيْهِ فَانْكِرَ ذَا بِكَ
عَلَيْهَا فَقَالَتْ وَاللهِ لَقَدْ صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى
(۲)
ابنى بَيْضَاءَ فِى الْمَسْجِدِ سُهَيْل وَ آخِيهِ - له
قد يروى أنَّ رَسُولُ
اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مُعْتَكِفا
لِهَذَا صَلَّى فِي الْمَسْجِدِ - له
یعنی حضرت عائشہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کی نماز جنازہ میت مسجد میں رکھوا کر
بڑھی.(۳) وَيُسْتَدَلُ لِجَوَانِ صَلوةِ النِّسَاءِ بِمَا أَخْرَجَهُ الْحَاكِيمْ انَّ رَبَا طَلْحَةَ
دَعَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عُمَيْرِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ حِيْنَ
تُونِي فَاتَاهُمْ رَسُولُ
الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى عَلَيْهِ فِي
مَنْزِلِهِمْ فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ أَبُو
طَلْعَةَ وَرَاثَهُ وَأَمِّ سَلَيْمٍ وَرَاءَ ابي طَلْعَةَ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ
غَيْرُهُمْ قَالَ الْعَالِمُ هَذَا حَدِيثُ صَحِيحٌ عَلَى شَيْءِ الشَّيْخَيْنِ
یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو طلحہ کے بیٹے عمیر کی نماز جنازہ ان کے گھر
میں پڑھی حضور آگے تھے ان کے پیچھے ابو طلحہ اور ان کے پیچھے ام سلیم صف بنا کر کھڑی تھیں.عَنِ ابْنِ عَبَاسِ قَالَ دَخَلَ النَّاسُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم
۳۸۵
مسلم كتاب
الجنائز باب الصلاة على الجنازة في المسجد بة تة : - مشكوة ابواب الجنائز مثلا حاشیه ت
: - اوجز المسالك شرح موطا امام مالک ص :
سل
Page 261
۲۵۵
ارْسَالَا يُصَلُّونَ عَلَيْهِ حَتَّى إِذَا فَرِفُوا أَدْخِلُوا النِّسَاءَ حَتَّى إِذَا شَرِفُوا
أدْخِلُوا الصَّبْيَانَ وَلَمْ يَومَ النَّاسُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَ
یعنی.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ عورتوں نے بھی پڑھی.تاہم اس جوانہ کے باوجود یہ بات مسلم ہے کہ عورتوں کے لئے خاص طور پر جنازہ کے ساتھ
نکلنا اور جنازہ کی نمازہ میں اہتمام کے ساتھ شامل ہونا پسند نہیں کیا گیا.مسجد میں میت رکھ کر نماز جنازہ ادا کرنا
عام علماء کا مسلک یہ ہے کہ جنازہ کی نمازہ مسجد سے باہر ہو.یعنی نیست اور نماز جنازہ پڑھنے
والے دونوں مسجد سے باہر ہوں.لیکن ضرورت یا مجبوری ہو تو مسجد کے اندر بھی نمازہ جنازہ ہو سکتی
ہے.میت کو بلا اثر مجبوری مسجد کے اندر نہیں رکھنا چاہیئے.بلکہ صورت یہ ہو کہ امام اور مقتدی
مسجد کے اندر صف باندھے ہوں اور میت مسجد سے باہر امام کی نظر کے سامنے ہو.حضرت خلیفہ مسیح الثالث ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز بعض اوقات اسی طریق کے مطابق جنازہ
پڑھاتے ہیں.تاہم نہ تو اس طرز عمل کو عادت بنا لینا چاہیئے اور نہ مقامی انتظامیہ کی باقاعدہ اجازت
کے بغیر اسے عام کرنا چاہیئے.بہر حال اس طریق عمل کے جو انہ کے لئے سند موجود ہے جس کے الفاظ یہ ہیں :-
" عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ انَّ عَائِشَةَ لَمَّا تُونِي سَعْدُ بْنُ أَبِي
وَقَاصِ قَالَتِ ادْخُلُوا بِهِ الْمَسْجِدَ حَتَّى أُصَلَّى عَلَيْهِ فَانْكِرَ ذَالِكَ
عَلَيْهَا فَقَالَتْ وَاللهِ لَقَدْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى
ابْنَي بَيْضَاء فِي الْمَسْجِدِ سُهَيْلِ وَأُخِيهِ - له
یعنی حضرت سعد بن وقاص کی جب وفات ہوئی تو حضرت عائشہ یہ معتکف تھیں.اس لئے
انہوں
نے کہلا بھیجا کہ میت مسجد میں لائی جائے تاکہ وہ بھی جنازہ میں شامل ہو سکیں.بعض لوگوں نے اس پر
اعتراض کیا تو آپ نے کہا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیضاء کے دو بیٹوں کا جناندہ (غالباً اعتکاف
کی وجہ سے یا بارش کے پیش نظر، مسجد میں پڑھا تھا.- حضرت ابو بکر و عمران کی نعش مبارک مسجد نبوی میں منبر اور روضہ کے درمیان رکھ کر نماز جنازہ ادا کی گئی تھی ہے
سه : - ابن ماجد کتاب الجنائز باب ذکر وفاته دوخته صلی اللہ علیہ وسلم ما ب سے مسلم كتاب الجنائز باب الصلوة على الجنازه وه :
عمر فاروق اعظم را از محمد حسین سیکل اردو ترجمه هنا :
Page 262
۲۵۶
-
حدیث کے الفاظ یہ ہیں :
عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَدَ انَّهُ قَالَ مُلَ عَلَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَابِ
في الْمَسْجِدِ "
۳ - صاحب شرح وقایہ لکھتے ہیں :-
كرِهَتْ فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ إِنْ كَانَ الْمَيْتُ فِيْهِ وَإِنْ كَانَتْ خَارِجَةٌ.......لا تَكْرَهُ عِنْدَ الْمَشَاخ - له
یعنی مسجد میں میت رکھ کر جنازہ پڑھنا بعض علماء کے نزدیک مکہ وہ اور نا پسندیدہ ہے لیکن
اگر نمازی مسجد میں ہوں اور میت مسجد سے باہر ہو تو یہ جائزہ ہے اور مکروہ نہیں ہے.سے
سوال : نماز جنازہ جوتیوں سمیت اور ننگے سر ادا کرنا کیسا ہے ؟
جواب.(الف) - حدیث میں یہ امر پوری وضاحت کے ساتھ آیا ہے کہ جوتی کے ساتھ نماز جائز ہے
حدیث کی ہر مشہور کتاب میں یہ روایت موجود ہے.ہم جو مساجد میں جوتیاں سے جانے سے
منع کرتے ہیں تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ مساجد میں صفائی رہے.دریاں اور فرش
گند سے نہ ہوں ورنہ یہ ممانعت کسی شرعی حکم کی وجہ سے نہیں ہے.نمازہ جنازہ چونکہ سجدے
باہر ہوتی ہے اس لئے جوتیاں پہن کہ نمازہ جنازہ ادا کر لینے میں کوئی حرج نہیں.(ب) ننگے سر نماز ادا کرنا پسندیدہ امر نہیں کیونکہ یہ امر بزرگوں اور سلف صالحین کے طریق
کے خلاف ہے اس لئے معیوب ہے.سوال :.نماز جنازہ بعد نماز عصر -
جواہے :.نماز جنازہ کسی وقت بھی ہو سکتی ہے.نماز عصر کے بعد بھی اور نما نہ فجر کے بعد بھی.اس میں
کوئی شرعی روک نہیں ہے.البتہ حنفی اور بعض مسلمان فرقے مکروہ اوقات میں نماز جنازہ
پسندیدہ نہیں سمجھتے.سے
سوال :.تدفین کے بعد نعش ایک ملک سے دوسرے ملک میں سے جانا نیز کتنے عرصہ بعد نعش
نکال سکتے ہیں.اور تابوت کی کیا سند ہے ؟
ے : موطا امام مالک باب الصلوة على الجنازة في المسجد مث ونصب الرايه قله ۲ : ۵۲:- شرح وقایہ ص ۲۵ :
:- نیز دیکھیں کتاب الفقه على المذاهب الاربعه من : : - الف، ترندی باب کرا تبر الصلوة على الجنازه قاب ، شرح وقایه كتاب الصلوة ما
Page 263
۲۵۰
جواب :.میت اگر ایک جگہ دفن ہوا اور ضرورت کی بناء پر اُسے دوسری جگہ یا دوسر نے ملک میں
منتقل کرنا ہو تو اس میں کوئی شرعی روک نہیں ہے.اصل مقصد میت کی توقیر ہے.اگر نعش
نکالنے کا مقصد اس کی تحقیرنہ ہو بلکہ کوئی مفید اور مسلم غرض ہو تو نعش کو قبر سے نکالا جاسکتا ہے
خصوصا جبکہ وہ بکس میں محفوظ ہو.ضرورت اور مصلحت کا فیصلہ مسلمانوں کے مرکزی نظام یا مقامی تنظیم کو کہ نا چاہئے.اصل
مقصد بو سے بچنا ہے اگر بو نہیں تو عرصہ کی تعیین کے بغیر بھی کیس نکالا جاسکتا ہے.عرصہ اور
مدت کوئی شرعی مسئلہ نہیں بلکہ اندازہ اور تجربہ کی بناء پر چھ ماہ یا سال کی مدت بنائی جاتی ہے کہ
اس عرصہ میں بالعموم بو ختم ہو جاتی ہے اور نعش خشک ہو جاتی ہے.(۳)
سابقہ فقہاء کی آراء اور بعض واقعات کے حوالے درج ذیل ہیں :-
كَانَ رَسُولُ
اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَدْخُصُ فِي نَقْلِ الْمَيِّتِ
وَنَبْشِ قَبْرِه لِمَصْلِحَةٍ - له
مَاتَ سَعْدُ بْنِ أَبِى وَقَاصِ وَسَعِيدُ بْن زَيْدٍ بِقَصْرِهِمَا بِالْعَتِيقِ
فعمِلَا إِلَى الْمَدِينَةِ وَدُفِنَا بِهَا - له
تُونَى عَبْدُ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بِالْعَبْتَهُ (اسمٌ مَكانٍ، فَحُمِلَ إِلَى
مَكَةَ وَدُيْنَ بِهَا.....حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہما السلام کی نعشیں مصر سے منتقل کر کے فلسطین
لائی گئیں.٥٣ ٢
(۵) تابوب کے جواز کے بارہ میں مندرجہ ذیل سند قابل مطالعہ ہے :-
(الف) لا بأس باتخاذ التَّابُوتِ وَلَوْ بِحَجْرٍ وَحَدِيدٍ عِنْدَ الْحَاجَةِ
كَرَ فَاوَةِ الْأَرْضِ -
اِسْتَحْسَن مَشَائِخُنَا اِتِّخَاذَ التَّابُوتِ لِلنِساءِ وَلَوْ لَمْ تَكُنِ
الْأَرْضُ رَخْوَةٌ فَإِنَّهُ اَقْرَبُ إِلى السَّتْرِ وَ التَّعَرُّرِ مَن مَتِهَا
عِنْدَ الْوَضْعِ فِي الْقَبْرِ م
۵۳۰۲۱ : کشف الغمر ص ا باب فى نقل الميت : : - (الف) طبرى الجزء اول تاریخ الائم
و الملوك ص ٣-٤ ) (ب) البدایہ والنہایہ ص۳۲ - (ج) رد المختار : - ه - - ردالمختار ص ٣
Page 264
Yox
سوال : جس گھر میں وفات ہو جائے تو وہاں قریبی رشتہ داروں اور پڑوسیوں کی طرف سے کھانے
بھیجنے کے بارہ میں کیا ہدایت ہے؟
جوا ہے :.وفات کے موقع پر میت والوں کے گھر میں پردیسیوں یا قریبی رشتہ داروں کی طرف سے دو
تین دن کھانا بھیجوانا مسنون ہے.حدیث میں آتا ہے :
;
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ لَمَّا جَاءَ نَحْى جَعْفَرٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصْنَعُو الأَهْلِ جَعْفَرِ طَعَا مَّا فَإِنَّهُ قَدْ جَاءَ هُمْ مَا يَشْفُلُهُمْ
یعنی حضرت عبد اللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب آپ کے والد حضرت
جعفر ینہ کی شہادت کی خبر آئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا.جفر کے اہل وعیال کے لئے
کھانا تیار کرو کیونکہ وہ جعفر کی وفات کے غم میں مبتلا ہیں اور کھانے کا اہتمام نہیں کر سکتے.زیارت قبور
شید نا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے زیارت قبور کے متعلق فرمایا :-
قبرستان میں ایک روحانیت ہوتی ہے اور صبح کا وقت زیارت قبور کے لئے ایک
سنت ہے یہ ثواب کا کام ہے اور اسی انسان کو اپنا مقام یاد آجاتا ہے.انسان اس
دنیا میں مسافر آیا ہے.آج زمین پر ہے تو کل زمین کے نیچے.حدیث شریف میں آیا ہے
که جب انسان قبروں میں آجاوے تو کہے اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْقُبُورِ مِنَ
المُؤمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَإِنَّا إِنْشَاء اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ أَسْأَلُ اللهَ
لَنَا وَ لَكُمْ الْعَافِيَة -
سوال :- قبرپر کیا دعا کرنی چاہئیے ؟
جواہ:.فرمایا.صاحب قبر کے واسطے دعائے مغفرت کرنی چاہئیے.اور اپنے واسطے بھی خُدا
سے دعا مانگنی چاہئیے.انسان ہر وقت خُدا کے حضور دعا کر نے کا محتاج ہے یے
مردوں کے لئے دعا کرنا
سوال: - قبر پر کھڑے ہو کر کیا پڑھنا چاہیے ؟
119
ترمذی ابواب الجنائز باب في الطعام يصنع لاهل الميت ملا ہے : مسلم كتاب الجنائز باب ما يقال عنه
دخول القبور - الخ ، ترندی باب ما يقول اذا دخل المقابر : ۱۳ - بدر شاه ۲۳ ، فتاوی مسیح موعود صله :
Page 265
۲۵۹
جوا ہے :.میت کے واسطے دُعا کرنی چاہئیے کہ خدا تعالٰی اس کے درجات کو بلند کرہ سے اور اگر اس نے
کوئی قصور کیا ہے تو اس کے قصوروں اور گناہوں کو بخشے اور ان کے پسماندگان کے واسطے
اپنے فضل کے سامان کر ہے.سوال : - دُعا میں کونسی آیت پڑھنی چاہئیے ؟
جوا ہے :.یہ تکلفات ہیں.تم اپنی زبان میں جس کو بخوبی جانتے ہو اور جس میں تم کو جوش پیدا ہوتا ہے
میت کے واسطے دُعا کرو.اے
سوال :.قبر پر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا جائز ہے یا نہیں ؟
جواب : قبر یہ ہاتھ اُٹھا کر دعا مانگنا جائز ہے ہے اور حدیث سے ثابت ہے حضرت امام بخاری اپنے
در سالہ رفع الیدین میں یہ حدیث لائے ہیں :-
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ
لَيْلَةٍ فَاَرْسَلْتُ بَرِيرَةً فِي اثْرِهِ لِتَنْظُرَ ايْنَ يَذْهَبُ فَسَلَكَ
نَحْوَ البَقِيعِ الْغَرْقَدِ فَوَقَفَ فِي أَدْنَى الْبَقِيْعِ ثُمَّرَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ
انْصَرَنَ فَرَجَعَتْ بَرِيرَةُ فَاَخْبَرَتْنِي فَلَمَّا اصْبَحْتُ سَأَلْتُهُ
فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْنَ خَرَجْتَ اللَّيْلَةَ قَالَ بُعِثْتُ إِلَى أَهْلِ
الْبَقِيْعِ لِأَصَلَّى عَلَيْهِمْ؟
یعنی حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ ایک رات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر
تشریف لے گئے.اُنہوں نے اپنی خادمہ حضرت بریرہ کو پیچھے بھیجا کہ جا کر دیکھو حضور کد ھر
جاتے ہیں.چنانچہ بریرہ نے واپس آکر بتایا کہ حضور جنت البقیع گئے تھے اور وہاں
حضور نے ہاتھ اُٹھا کر دعا کی.صبح حضرت عائشہ ہو نے حضور سے پو چھا کہ آپ رات کس
لئے باہر گئے تھے تو آپ نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا تھا کہ میں جنت البقیع
میں مدفون اپنے صحابہ کے لئے دعا کروں.14.4
: بدر شاه، فتاویٰ حضرت مسیح موعود هنا : ٥٣:- الفضل ١٨ مارچ.سے :- (الف) مسلم باب ما يقال عند دخول القبر والدعاء لاهلها مكة
(ب ) حاشیہ المنتقى من اخبار المصطفى ۳۳۵ مطبوعہ مطبع رحمانی دہلی ۳۳۴ده به
Page 266
۲۶۰
قبر میں سوال وجواب
سوال :- قبرس سوال و جواب رُوح سے ہوتا ہے یا جسم میں وہ روح واپس ڈالی جاتی ہے ؟
جوا ہے : سید نا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا :-
اس پر ایمان
لانا چاہیے کہ قبر میں انسان سے سوال وجواب ہوتا ہے لیکن
اس کی تفصیل اور کیفیت کو خُدا پر چھوڑنا چاہیئے.یہ معاملہ انسان کا خدا کے ساتھ ہوتا
ہے وہ جس طرح چاہتا ہے کرتا ہے.پھر قر کا لفظ وسیع ہے جب انسان مر جاتا ہے تو
اس کی حالت بعد الموت میں جہاں خُدا اس کو رکھتا ہے وہی قبر ہے خواہ دریا میں فرق
ہو جا و سے خواہ جل جاوے خواہ زمین پر پڑا ر ہے.دنیا سے انتقال کے بعد انسان
قبرمیں ہے اور اسی مطالبات اور مواخذات جو ہوتے ہیں اس کی تفصیل کو اللہ تعالیٰ
بہتر جانتا ہے.انسان کو چاہیے کہ اس دنیا کے لئے تیاری کرے نہ کہ اسکی کیفیت
معلوم کرنے کے پیچھے پڑے " اے
سوال: - سماع موتی کے بارہ میں جماعت احمدیہ کا مسلک کیا ہے ؟
جوا ہے : ہمارے نزدیک فوت شدہ اس دُنیا کے رہنے والوں کی باتیں براہ راست نہیں سُن
سکتے.البتہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ یہاں کے رہنے والوں کی باتیں ان تک پہنچا سکتا ہے.اور بعض اوقات مصلحت کی بناء پر پہنچاتا بھی ہے.اسی طرح مرنے والے اللہ تعالیٰ کی اجازت
اور توفیق کے مطابق دنیا والوں کے لئے دعائیں بھی کرتے ہیں لیکن چونکہ ان سب امور کا تعلق براہِ
راست اللہ تعالیٰ کی مرضی اور ارادہ کے ساتھ ہے اس لئے اس کے متعلق وہی طریق اختیار کرنا
چاہیئے جس کی اجازت شریعیت نے بالوضاحت دی ہے مثلاً ان کے حق میں دعا کرنا انہیں ثواب
پہنچانے کے لئے رسم و رواج سے بچ کر صدقہ و خیرات
کرنا.اظہار تعلق کا بہترین ذریعہ ہے.اس صورت میں اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو مرنے والوں کو بھی اس کی اطلاع کر دے گا.اور وہ بھی
اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے اپنے پسماندگان کے لئے دعا کریں گے.براہ راست مردوں کو
مخاطب کرنا کہ وہ اس کے لئے دعاء کریں یا اس کا یہ کام کر دیں ایک نزنگ کا شرک ہے جسے
اسلام پسند نہیں کرتا.: - بدر ۱۴ فروری شنشله :
Page 267
۲۶۱
مُردوں کو سلام اور اگنے کا سننا
سوال -: - السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْقُبُورِ جو کہا جاتا ہے کیا مردے سُنتے ہیں ؟
جواب : سید نا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا :-
و دیکھو وہ سلام کا جواب وَعَلَيْكُمَ السّلام تو نہیں دیتے.خُدا تعالیٰ وہ سلام
جو ایک دُعا ہے پہنچا دیتا ہے.اب ہم جو آواز سنتے ہیں اس میں ہوا ایک واسطہ ہے
لیکن یہ واسطہ مردہ اور تمہارے درمیان نہیں.لیکن سَلامُ عَلَيْكُمْ میں خُدا تعالے
ملائکہ کو واسطہ بنا دیتا ہے.اسی طرح درود شریف ہے کہ ملائکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو
پہنچا دیتے ہیں یہ لے
مردہ کی آواز
سوال : کیا مُردہ کی آواز دنیا میں آتی ہے؟
: خدا تعالی کی آواز تو ہمیشہ آتی ہے مگر مردوں کی نہیں آتی.اگر کبھی کسی مردے کی آواز آتی ہے
تو خدا تعالی کی معرفت یعنی خدا تعالٰی کوئی خبر ان کے متعلق دے دیتا ہے.اصل یہ ہے کہ کوئی ہو خواہ
نبی ہو یا صدیق یہ حال ہے کہ آن را که خبر شد خبرش باز نیامد اللہ تعالی ان کے درمیان اور
اہل و عیال کے درمیان ایک حجاب لکھ دیتا ہے وہ سب تعلق قطع ہو جاتے ہیں.اس لئے
فرماتا ہے " فَلَا انْسَابَ بَيْنَهُمْ ، له
مرنے پر کھانا کھلانا
سوال :.دیہات میں دستور ہے شادی غمی کے موقع پر ایک قسم کا خرچ کرتے ہیں.کوئی چودھری مر جاوے
تو تمام مسجدوں ، دواروں و دیگر کمیوں کو بحصہ رسدی کچھ دیتے ہیں.اس کی نسبت حضور کا کیا
ارشاد ہے ؟
جواب : سید نا حضرت مسیح موعود علیہ الصلواۃ والسلام نے فرمایا : -
طعام جو کھلایا جاو سے اس کا مردہ کو ثواب پہنچ جاتا ہے.گو ایسا مفید نہیں جیسا کہ
وہ اپنی زندگی میں خود کرتا ہے.عرض کیا گیا حضور وہ خرچ وغیرہ کمیوں میں بطور حق الخدمت
: :
بدر ۷ ار مارچ منشله ۱۲- فتادی احمدیہ صلا : :
Page 268
۲۶۲
تقسیم ہوتا ہے.فرمایا.تو پھر کچھ ہرج نہیں.یہ ایک علیحدہ بات ہے کسی کی خدمت کا حق تو دینا چاہیے.عرض کیا گیا کہ اس میں فخر و ریاء تو ضرور ہوتا ہے یعنی دینے والے کے دل میں یہ ہوتا
ہے کہ مجھے کوئی بڑا آدمی کہے.فرمایا.یہ نیت ایصال ثواب تو وہ پہلے ہی خرچ نہیں.حق الخدمت ہے.بعض ریاء شرعاً بھی جائز ہیں مثلا چندہ وغیرہ.نماز با جماعت ادا کرنے
کا جو حکم ہے تو اسی لئے کہ دوسروں کو ترغیب ہو.غرض اظہار و اخفاء کے لئے مواقع
ہیں.اصل بات یہ ہے کہ شریعت سب رسوم کو منع نہیں کرتی.اگر ایسا ہوتا تو پھر
ریل پر چڑھنا.تارو ڈاک کے ذریعہ خبر منگوانا سب بدعت ہو جائے ؟ لے
دسویں محرم کو خیرات
کوخیرا
سوال :.محرم کی دسویں کو جو شربت و چاول و غیر تقسیم کرتے ہیں اگر یہ اللہ بہ بیت ایصال ثواب
ہو تو اس کے متعلق حضور کا کیا ارشاد ہے ؟
جواہے :.فرمایا " ایسے کاموں کے لئے دن اور وقت مقرر کرنا ایک رسم و بدعت ہے اور آہستہ
آہستہ ایسی رسمیں شرک کی طرف لے جاتی ہیں.پس اس پر سیز کرنا چاہیئے.کیونکہ ایسی
ریموں کا انجام اچھا نہیں.ابتداء میں اسی خیال سے مگر اب تو اس نے شرک اور غیر اللہ
کے نام کا رنگ اختیار کر لیا ہے اس لئے ہم اسے ناجائنہ قرار دیتے ہیں.جب تک
ایسی رسوم کا قلع قمع نہ ہو عقائد باطلہ دور نہیں ہوتے " کے
مُردہ کے لئے قرآن خوانی
" مُردہ کے لئے قرآن پڑھنے کے متعلق فرمایا کہ اُسے قرآن
کریم کا ثواب نہیں پہنچتا
مگر صدقہ و خیرات کا ثواب مُردے کو پہنچتا ہے کیونکہ قرآن کا پڑھنا عبادت ہے.صدقہ
بھی مردے کے اعمال میں نہیں لکھا جاتا بلکہ کسی اور رنگ میں اس کو ثواب ملتا ہے" سے
مردہ کا ختم و اسقاط میت
سوال ہے :.مروہ کا ختم وغیرہ جو کرایا جاتا ہے یہ جائز ہے یا نا جائز ؟
بلکه ۱۷ جنوری خنشله -سه-: بدر ۲ از مارچ شاه : ه:- الفضل ۳ جولائی شائر :
Page 269
۳۶۳
جوا ہے :." اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے صرف دُعا اور صدقہ میت کو پہنچتی ہے.مومن کو
چاہیے کہ نماز پنجگانہ ادا کرے اور رکوع سجود میں میت کے لئے دُعا کرے.یہ طریق
نہیں ہے کہ الگ کلام پڑھ کر بجتے.اب دیکھو لغت کا کلام منقول چلا آتا ہے کسی کا
حق نہیں ہے کہ اپنی طرف معنے گھڑے.ایسے ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے
جو امر ثابت ہو اس پر عمل کرنا چاہیے.نہ کہ اپنی من گھڑت پر ایک طریق اسقاط کا
رکھا ہے کہ قرآن شریف کو چکر دیتے ہیں.یہ اصل میں قرآن شریف کی بے ادبی ہے.انسان خُدا سے سچا تعلق رکھنے والا نہیں ہو سکتا.جب تک سب نظر خدا پر نہ ہو.اے
مردہ کی استقاط
سوال -: - لوگ مُردہ کے پاس کھڑے ہو کر اسقاط کراتے ہیں کیا اس کا کوئی طریق جائز ہے ؟
جواہے :.فرمایا یہ اس کا کہیں ثبوت نہیں ہے.ملاؤں نے ماتم اور شادی میں بہت سی
ریمیں پیدا کر لی ہیں یہ بھی ان میں سے ایک ہے " ۲
میت کے لئے قل
سوال : میت کے لئے قل جو تیسرے دن پڑھے جاتے ہیں ان کا ثواب اسے پہنچتا ہے
جوار
نہیں؟
جو اسے " قل خوانی کی کوئی اصل شریعیت میں نہیں ہے دُعا اور استغفار میت کو پہنچتی ہے.ہاں یہ ضرور ہے کہ ملانوں کو اسے ثواب پہنچ جاتا ہے.سو اگر انہیں ہی کو مردہ تصویر
کر لیا جاد سے تو ہم مان لیں گے.ہمیں تعجب ہے کہ یہ لوگ ایسی باتوں پر امید کیسے
باندھ لیتے ہیں.دین اسلام تو ہم کو نبی کریم سی للہ علیہ وسلم سے ملا ہے اس میں ان
باتوں کا نام تک نہیں.صحابہ کرام یہ بھی فوت ہوئے.کیا کسی کے قتل پڑھے گئے
صد ہا سال بعد اور بدعتوں کی طرح یہ بھی ایک بدعت نکل آئی ہوئی ہے" سے
مُردہ کے فاتحہ خوانی
سوال : کسی کے مرنے کے بعد چند روز لوگ ایک جگہ جمع رہتے ہیں اور فاتحہ خوانی کرتے ہیں فاتحہ خوانی
را
ه بدر ۱۰ مارچ سنشاه: در ۲۴ ر ا پریل شار: ۱۳ بدر ۱۹ ز مارچ شه :
ས
Page 270
۲۶۴
ایک دعائے مغفرت ہے.پس اس میں کیا مضائقہ ہے ؟
جواب :.فرمایا یہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ وہاں سوائے غیبت اور بے ہودہ بکو اس کے اور کچھ
نہیں ہوتا.پھر یہ سوال ہے کہ آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام و ائمہ عظام میں
سے کسی نے یوں کیا.جب نہیں کیا تو کیا ضرورت ہے.خواہ مخواہ بدعات کا دروازہ
کھولنے کی.ہمارا مذہب تو یہی ہے کہ اس رسم کی کچھ ضرورت نہیں.ناجائز ہے.اے
ختم اور ختم کیے لوڑیاں
سوال : ختم کی ریوڑیاں وغیرہ سے کہ کھانی چاہئیں کہ نہ ؟
جوا ہے : " ختم کا دستور بدعت ہے.شرک نہیں ہے.اس لئے کھا لینی جائز ہیں.لیکن
ختم دلوانا نا جائز ہے اور اگر کسی پیر کو حاضر و ناظر جان کر اس کا کھانا دیا جاتا ہے
وہ ناجائز ہے " ہے
مرده پر نوحه
" ماتم کی حالت میں جزع فزع اور نوحہ یعنی سیا پا کرنا اور چیخیں مار کر رونا اور
بے صبری کے کلمات زبان پر لانا.یہ سب ایسی باتیں ہیں جن کے کرنے سے ایمان کے
جانے کا اندیشہ ہے اور یہ سب رسمیں ہندوؤں سے لی گئی ہیں.جاہل مسلمانوں نے
اپنے دین کو بھلا دیا اور ہندوؤں کی رسمیں اختیار کر لیں کیسی عزیز اور پیار سے کی موت کی
حالت میں مسلمانوں کے لئے یہ حکم قرآن شریف میں ہے کہ صرف إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ
راجعون کہیں.یعنی ہم خُدا کا مال اور ملک ہیں اسے اختیار ہے جب چاہے اپنا
مال لے لے اور اگر رونا ہو تو صرف آنکھوں سے آنسو بہانا جائز ہے اور جو اسے
زیادہ کر سے وہ شیطان ہے.براہر ایک سال تک سوگ رکھنا اور نئی نئی عورتوں کے
آنے کے وقت یا بعض خاص دنوں میں سیا پا کرنا اور باہم عورتوں کا سٹر کرا کر چلانا ہونا
اور کچھ کچھ منہ سے بھی بکو اس کرنا اور پھر برابر ایک برس تک بعض چیزوں کا پکانا چھوڑ
دینا اس عذر سے کہ ہمارے گھرمیں یا ہماری برادری میں ماتم ہوگیا ہے یہ سب نا پاک
رسمیں ہیں اور گناہ کی باتیں ہیں جن سے پر ہیز کرنا چاہیئے “ کے
: بدر ۱۶ مارچ شده ، ۱۹ مئی شله : ۵۳:- بدر ۱۶ پارچ له سه : فتادی مسیح موعود منا :
Page 271
قبر سگی بنانا
۲۶۵
سوال :.میں اپنے بھائی کی پکی قبر بناؤں یا نہیں ؟
جوا ہے :" اگر نمود اور دکھلاوے کے واسطے پکی قبریں اور نقش
و نگار اور گنبد بنائے جاویں تو یہ حرام
ہے.لیکن اگر خشک ملا کی طرح یہ کہا جاو ہے کہ ہر حالت اور ہر مقام میں کچی ہی اینٹے لگائی جاؤ سے
تو یہ بھی حرام ہے.إِنَّمَا الاَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ عمل نیت پر موقوف ہے.ہمارے نزدیک بعض
وجوہ میں کچی کرانا درست ہے.مثلاً بعض جگہ سیلاب آتا ہے بعض جگہ قبر میں میت کو کتنے اور
بجو وغیرہ نکال لے جاتے ہیں.مُردے کے لئے بھی ایک عزت ہوتی ہے.اگر ایسی وجود پیش
آجائیں تو اس حد تک کہ نمود اور شان نہ ہو بلکہ صدمہ سے بچانے کے لئے قبر کا پکا کرنا جائز
ہے.اللہ اور رسول نے مومن کی لاش کے لئے بھی عزت رکھی ہے.ورنہ معزت ضروری
نہیں تو غسل دینے کفن دینے.خوشبو لگانے کی کیا ضرورت ہے.مجوسیوں کی طرح جانوروں
کے آگے پھینک دو.مومن اپنے لئے ذلت میں رہنا نہیں چاہتا.حفاظت ضروری ہے.جہاں
تک نیست صحیح ہے خُدا تعالیٰ مؤاخذہ نہیں کرتا.دیکھو مصلحت انہی نے یہی چاہا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پختہ گنبد ہوا اور کئی
بزرگوں کے مقبرے پختہ ہیں.مثلاً نظام الدین فرید الدین - قطب الدین معین الدین رحم الله
علیہم.یہ سب صلحاء تھے “ لے
قبه یا روضہ بنانا
حضرت خلیفہ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا :-
" اگر قبر کی حفاظت کے لئے ضروری نہ ہو تو قبہ وغیرہ کی ضرورت نہیں.اور اگر
یادگار کے خیال سے قبہ بنایا جائے توئیں ایسی یادگار
کا قائل نہیں کہ اس کے لئے قبہ
ضروری ہو.یہی خیال ہے جسے آگے شرک پیدا ہوتا ہے.پس پروڈکشن (حفاظت)
تو ٹھیک ہے لیکن میموریل زیاد گار ٹھیک نہیں کیونکہ قبر کی اس رنگ میں یاد گا ر ہی وہ
چیز ہے جو آگے شرک تک پہنچا دیتی ہے.بے شک ہم تو احترام کے طور پر قبے بنائیں
گے لیکن دوسرے لوگ اس احترام کو اس حد تک پہنچا دیں گے کہ جس کی شرک شروع
۹۲
الحكم ارمی نشائه - فتاوی مسیح موعود هشت ۹۳.
Page 272
۲۶۶
ہو جائے گا.رسول
کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر جو قبہ بنایا گیا ہے وہ بھی حفاظت کے
لئے ہے نہ کہ اس لئے کہ مزار کی عزت کی جائے " اے
سوال :.قبروں پر قبہ بنانا کیوں جائز نہیں ؟
جواب : انسان کی فطرت میں رکھا گیا ہے کہ جن وجودوں کے ساتھ اسے محبت ہوتی ہے
ان کے مرنے کے بعد بھی جہاں تک ہو سکے ان
کا احترام کرنا چاہتا ہے یوں تو جب کوئی
شخص مرجاتا ہے اس کی لاش اگر کتے بھی کھا جائیں تو اُسے کیا تکلیف ہوگی لیکن اسے
محبت رکھنے والے جو زندہ انسان ہوں ان کی فطرت گوارا نہیں کرتی کہ لاش کی یہ حالت
ہو.اس لئے وہ اپنے طور پر اس کا احترام کرتے ہیں.مگر یہ کوئی شرعی احترام نہیں ہوتا.کیونکہ شرعی طور پر احترام جانہ نہیں.کیونکہ اسکی شرک پھیلتا ہے.بچوں وغیرہ کی قبر
پر کوئی قبہ نہیں بنا تا مگر بزرگوں کی قبر پر قبہ بناتے ہیں کیونکہ ان کی غرض ہی یہ ہوتی ہے
کر ان سے کچھ حاصل ہوگا " ہے
مزار کو بوسہ دنیا
ایک شخص نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مزار کو بوسہ دینے کے متعلق پوچھا.حضرت
خلیفہ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا :-
دو یہ جائز نہیں لغو بات ہے.اس قسم کی حرکات سے شرک شروع ہوتا ہے اصل چیز
نبی کی تعلیم پرعمل کرنا ہے مگر لوگ اسے چھوڑ کر لغو باتوں میں جاپڑے ہیں یہ تے
له : - الفصل یکم مارچ ۱۹۲۶ ۶ به ۲ : - الفضل یکم مارچ ۲ : سه :- الفصل ۱۸ مئی :
Page 273
۲۶۷
روزه
اسلامی عبادات کا دوسرا اہم رکن روزہ ہے.روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں نفس کی
تہذیب اس کی اصلاح اور قوت برداشت کی تربیت مد نظر ہوتی ہے.حضرت مسیح موعود علیہ السّلام
فرماتے ہیں :-
" جس دین میں مجاہدات نہ ہوں وہ دین ہمارے نزدیک کچھ نہیں لے
صوم (روزہ ) کے لغوی معنی رکھتے اور کوئی کام نہ کرنے کے ہیں.شرعی اصطلاح میں طلوع فجر
ر صبح صادق سے لے کہ غروب آفتاب تک عبادت کی نیت سے کھانے پینے اور جماع سے لے کے رہنے
کا نام صوم یا روزہ ہے.اللہتعالٰی قرآن کریم میں فرماتا ہے كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ
الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ اَتِمُّوا القِيَامَ إِلَى اللَّيْلِ :
رات کے وقت کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہیں سفید دھاری سیاہ دھاری سے الگ نظر
آنے لگے.یعنی فجر طلوع ہو جائے تو اس کے بعد رات آنے تک سارا دن روزہ کی تکمیل میں لگے
رہو.خُدا کی خاطر اور اُس کی رضا کے حصول کے لئے کھانے پینے اور جنسی خواہش سے رکنے کا حکم ہر
قسم کی برائیوں سے بچنے کے لئے بطور علامت ہے.جیسے آنحضرت صلی للہ علیہ وسلم نے فرمایا." مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ النُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ اللَّهِ حَاجَةٌ فِي
ان يدعَ طَعَامَهُ وَشَرَايَة» له
یعنی ” جو شخص روزہ میں جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے اللہ تعالیٰ کو اس کے
کھانا پینا چھوڑنے کی کیا ضرورت؟
جب اصل مقصد حاصل کرنے کا جذبہ ہی نہیں تو روزہ کا کیا فائدہ.اسی طرح ایک اور موقع
پر فرمایا :
لَيْسَ القِيَامُ مِنَ الْأَيْلِ وَالشُّرْبِ وَإِنَّمَا القِيَا مُمِنَ اللَّفُودَ الرَّنت
فإن سابَكَ اَحَدٌ اَوْجَهِلَ عَلَيْكَ فَقُلْ إِنِّي صَائِمُ إِنِّي صَائِمٌ نَكُمْ
مِن صَائِم لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الْجُوعُ وَالْعَطَشُ وَكَمْ مِنْ قَائِم
۲۵۵
ه : فتاوی احمدیه ملت : ه :- بقره : مثلا : ۹۳ : - بخاری کتاب الصوم ۲ :
Page 274
Рул
لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِ إِلَّا السَّهَرُ له
یعنی روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں بلکہ ہرقسم کی بیہودہ باتیں کرنے اور فحش
کہنے سے رکنے کا مفہوم بھی اس میں شامل ہے.پس اسے روزہ دار اگر کوئی شخص تجھے گالی دے
یا غصہ دلائے تو تو اُسے کہدے کہ میں روزہ دار ہوں.جو شخص روزہ دار ہونے کے باوجود گالی
گلوچ کرتا ہے تو اس کا روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنا ہے جیسی اسے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا.قدیم مذاہب میں روزہ..روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا وجود قدیم سے قدیم مذاہب میں بھی ملتا ہے.چنانچہ اس
کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالی فرماتا ہے :-
كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
اسے مسلمانو! تم پر روزہ رکھنا اسی طرح فرض کیا گیا ہے جس طرح ان لوگوں پر فرض کیا گیا تھا
جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں اور اس کی غرض تقویٰ کا حصول اور تہذیب نفس ہے.اسلامی روزوں اور قدیم مذاہب کے روزوں کی شکل میں گو اختلاف ہے مگر بنیادی عناصر سب
میں مشترک ہیں.حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے :-
" فَضْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ اَهْلِ الْكِتَابِ أَكَلَةُ السَّحَرِ " "
ہمارے اور اہلِ کتاب کے روزوں میں ایک فرق سحری کھانا بھی ہے.مسلمان سحری کھا کر روزہ
رکھتے ہیں اور اہل کتاب سحری نہیں کھاتے.اسی طرح ہندو اپنے روزہ کے دوران میں کئی چیزیں
کھا بھی لیتے ہیں پھر بھی ان کا روزہ قائم رہتا ہے گویا ان کے ہاں صرف بعض چیزوں سے پر ہیز
کا نام روزہ ہے.عیسائیوں کے روزے بھی اسی قسم کے ہیں کہ کسی روز سے میں گوشت نہیں کھانا.کسی میں خمیری روٹی نہیں کھائی.بعض مذاہب میں پورے دن رات کا روزہ بغیر سحری کھائے ہوتا
ہے.وہ صرف شام کے وقت افطار کرتے ہیں کیسی مذہب میں چار چار دن متواتر روزہ رکھنے کا حکم
ہے.بعض مذاہب میں ایسے روز نے بھی پائے جاتے ہیں جن میں صرف ٹھوس غذا کھانے سے منع
144
ه : - دار می مسحواله مشکواة :
:- بقره : ۱۸۲
: - مسند دار می بافضل المسحور ما ، حاشيه المنتقى من اخبار المصطفے مطبوعہ رحمانی رہی ۳۳ :
Page 275
کیا گیا ہے.اور ہلکی غذا دودھ پھل وغیرہ کے استعمال کی اجازت ہے.روزہ کی غرض
روزه اصلاح نفس کا ذریعہ ہے کیونکہ جہاں انسان خُدا کی خاطر لذات کو ترک کر دیتا ہے وہاں
اسے اپنے نفس کو زیادہ سے زیادہ نیکی پر قائم کرنے اور ہر قسم کی حرام اور نجس چیزوں سے پر ہیز
کی کوشش کرنے کا سبق بھی اسے ملتا ہے.1
حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں :-
روزوں
کی عرض کسی کو بھوکا یا پیاسا مارنا نہیں ہے.اگر بھو کا مرنے سے جنت
مل سکتی توئیں سمجھتا ہوں کا فرسے کا فر اور منافق سے منافق لوگ بھی اس کے لینے کے لئے
تیار ہو جاتے کیونکہ بھوکا پیاسا مر جانا کوئی مشکل بات نہیں.در حقیقت مشکل بات اخلاقی اور روحانی تبدیلی ہے.لوگ بھوکے تو معمولی معمولی
باتوں پر رہنے لگ جاتے ہیں.قید خانوں میں جاتے ہیں تو بھوک ہڑتال (مرن برت )
شروع کر دیتے ہیں اور برہمنوں کا تو یہ مشہور حیلہ چلا آتا ہے کہ جب لوگ ان
کی کوئی بات
نہ مانیں تو کھانا چھوڑ دیتے ہیں.بس بھوکا رہنا تو کوئی بڑی بات نہیں اور نہ یہ رمضان
کی غرض ہے.رمضان کی اصل عرض یہ ہے کہ اس ماہ میں انسان خُدا تعالٰی کے لئے ہر ایک چیز
چھوڑنے کے لئے تیار ہو جائے اس کا بھوکا رہنا علامت اور نشان ہوتا ہے اس بات
کا کہ وہ اپنے ہر حق کو خُدا کے لئے چھوڑنے کے لئے تیار ہے.کھانا پینا انسان کا حتی ہے
میاں بیوی کے تعلقات اس کا حق ہے اس لئے جو شخص ان باتوں کو چھوڑتا ہے وہ یہ
بتاتا ہے کہ میں خدا تعالیٰ کے لئے اپنا حق چھوڑنے کے لئے تیار ہوں.ناحق کا چھوڑنا تو
بہت ادنی بات ہے اور کسی مومن سے یہ امید نہیں کی جا سکتی کہ وہ کسی کا حق مارے
مؤمن سے جس بات کی امید کی جا سکتی ہے وہ یہی ہے کہ خُدا تعالیٰ کی رضاء کے لئے اپنا
حقی بھی چھوڑ دے.لیکن اگر رمضان آئے اور یونہی گذر جائے درہم یہی کہتے رہیں کہ ہم
اپنا حتی کس طرح چھوڑ دیں تو اس کا مطلب یہ ہو گا کہ ہم نے رمضان سے کچھ حاصل نہ کیا کیونکہ
رمضان یہی بتانے کے لئے آیا تھا کہ خدا کی رضا کیلئے اپنے حقوق بھی چھوڑ دینے چاہئیں" نے
: - الفضل ۳۰ مارچ.۶۰۵
Page 276
حضرت خلیفہ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ :
جو انسان روزہ میں اپنی چیزیں خدا کے لئے چھوڑتا ہے جن کا استعمال کرنا اس کے لئے کوئی
قانونی اور اخلاقی جرم نہیں تو اسی اسے عادت ہوتی ہے کہ غیروں کی چیزوں
کو ناجائز طریق
سے استعمال نہ کرے اور ان کی طرف نہ دیکھے اور جب وہ خُدا کے لئے جائنہ چیزوں کو
چھوڑتا ہے تو اس کی نظر نا جائز چیزوں پر پڑ ہی نہیں سکتی ہے
غرض جہاں روزہ سے تزکیہ نفس و تجلی قلب ہوتی ہے وہیں روزہ جسمانی ، اخلاقی اور معاشرتی فوائد کا
موجب بھی بن جاتا ہے اسی کشفی طاقت بڑھتی اور ترقی پذیر ہوتی ہے جس طرح جسمانی روٹی سے جسم
کو قوت ملتی ہے ایسا ہی روحانی روٹی دیعنی روزہ کی حالت، روح کو قائم رکھتی ہے اور اس سے روحانی
قوالی تیز تر ہوتے ہیں.اسی لئے فرمایا : " أن تَصُومُوا خَيْرُ تَكُمْ نه یعنی اگر تم روزہ رکھ ہی
لیا کرو تو اس میں تمہارے لئے بڑی خیر ہے.قرآن کریم میں روزہ کو متقی بننے کا ایک مجرب نسخہ بتایا گیا ہے.یعنی اگر تم اس نسخہ پر عمل کرد گے
تو متقی بن جاؤ گے.فرمایا :-
" يَاَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ
مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ له
ترجمہ :.اسے لوگو جو ایمان لائے ہو تم پر بھی روزوں کا رکھنا اسی طرح فرض کیا گیا ہے جس
طرح اُن لوگوں پر فرض کیا گیا تھا جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں تاکہ تم روحانی اور اخلاقی
کمزوریوں سے بچو.در جس قدر بدیاں پیدا ہوتی ہیں ان کا منبع چار چیزیں ہیں باقی آگے اس کی فروع ہیں.وہ چار منابع یہ ہیں.اول - کھانا.دوئم پینا.سوئم شہوت.چہارم حرکت سے
بچنے کی خواہش.سب عیوب ان چاروں باتوں سے تعلق رکھتے ہیں.ان چاروں منبعوں کو بدی سے
روکنے کے لئے روزے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے مثلاً ایک شخص خیانت اس لئے کہتا ہے
کہ محنت سے بچنا چاہتا ہے یعنی محنت کر کے کھانا نہیں چاہتا اور دوسرے کا مال کھاتا
ہے.لیکن روزہ دار کو رات کے زیادہ حصہ میں اُٹھ کو عبادت کرنی پڑتی ہے.سحری کے لئے
اُٹھتا ہے.سارا دن مونہ بند رکھتا ہے.سو تا کم ہے.ایک ماہ تک روزے دار کو یہ
له الفضل
×1944
مشن : بقره ۱۸۵۱ : ۵۳ : بقره : ۱۸۴ :
Page 277
تکلیف اٹھانی پڑتی ہے جس سے اس کا جسم عادی ہو جاتا ہے اور اس سے غفلت کی عادت
کو دھکا لگتا ہے.پھر کھانے پینے اور شہوت سے بدیاں پیدا ہوتی ہیں.ان کے لئے بھی
روزہ رکھا گیا ہے.انسان کھانا پینا ترک کرتا ہے ضروریات زندگی کو چھوڑتا ہے.پیس
جن ضرورتوں کے باعث انسان گناہ میں پڑتا ہے انہیں عارضی طور پر روک دیا جاتا ہے یہ لے
روزہ کا جسمانی فائدہ بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ انسانی جسم تکالیف اور شدائد برداشت کرنے کا
عادی ہو جاتا ہے اور اس وجہ سے اس میں قوت برداشت اور صبر کا مادہ پیدا ہوتا ہے علاوہ ازیں
صحت کے برقرار رکھنے میں فاقہ کی طبی اہمیت مسلم ہے.اگر اعتدال پیش نظر رہے تو اسی سے
صحبت میں نمایاں فرق پڑتا ہے.گویا روزہ جسم کی صحت کا ضامن ہے اور روحانی لحاظ سے تقویٰ
کا منبع اور سرچشمہ ہے.اس سے خوش خلقی - عفت - دیانت.نیک چینی اور تزکیہ نفس کی توفیق
ملتی ہے.صبر و جرات کی قوتوں کی نشو و نما ہوتی ہے.غرباء کی تکالیف کا احساس ہوتا ہے اور
ان کی مدد کرنے کا جذبہ بڑھتا ہے اور اس طرح اقتصادی اور طبقاتی مساوات کے رحجانات کو
فروغ ملتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ صحت بھی بر قرارہ ر ہتی ہے.روزہ رکھنے والے کا درجہ
حدیث قدسی ہے : كُل عَمَلِ ابنِ دَمَلَهُ إِلَّا الصِّيَامُ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا
اجْرِى بِهِ وَالصّيَامُ جُنَّة له
- وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ تَخَلُوتُ فَمِ الصَّائِهِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ
مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ - ٣
یعنی.انسان کے سب کام اس کے اپنے لئے ہیں مگر روزہ میرے لئے ہے اسلیئے
میں خود اس کی جزا بنوں گا.کیونکہ وہ اپنی تمام خواہشات اور کھانے پینے کو میری خاطر
چھوڑ دیتا ہے.نیز فرمایا :
قسم ہے اس ذات کی جس کی قبضہ قدرت میں محمد صلی الہ علیہ وسلم )
کی جانی ہے
روز سے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کستوری سے بھی زیادہ پاکیزہ اور خوشگوار ہے.اسی طرح فرمایا :-
۲۵۵
ه الفضل ا د کبر له سه : - بخاری کتاب الصوم ص : ه : بخاری کتاب الصوم ما :
Page 278
۲۷۲
مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.له
جو شخص ایمان کے تقاضے کے مطابق اور ثواب کی نیت سے رات کو اُٹھ کر نماز پڑھتا ہے
اور روزہ رکھتا ہے اس کے گذشتہ گناہ بخش دیئے جاتے ہیں.روزوں کی اقسام
متعدد قیموں کے روزوں کا ذکر قرآن وحدیث میں پایا جاتا ہے مثلاً فرض روزہ ہے.نفلی روزے.فرض روزوں کی مثال جیسے رمضان کے روزے.رمضان کے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضاء-
کفارہ ظہار کے روزے.کفارہ قتل کے روزے.حمد رمضان کا روزہ توڑ دینے کی سزا کے شاٹھ
روز سے.کفارہ قسم کے روزے.کے روزے.نذر کے روزے.حج تمتع یا حج قران کے روزے.بحالت
احرام شکار کرنے کی وجہ سے روزہ.بحالت احترام سر منڈوانے کی وجہ سے روزہ.دوسری قسم نفلی روزوں کی ہے جیسے.شوال کے چھ روز سے.عاشورہ کا روزہ قوم داؤد علیہ السلام
یعنی ایک دن روزہ اور ایک دن افطار - یوم عرفہ کا روزہ.ہر اسلامی مہینے کی ۱۳ - ۱۴- ۱۵ تاریخ کا
روزه -
بعض دنوں میں روزہ رکھنا منع اور مکروہ ہے مثلاً صرف ہفتہ یا جمعہ کے دن کو خاص کر کے روزہ رکھنا
پارسیوں کی طرح نیروز و مہرگان کے دن روزہ رکھتا.صوم و ہر یعنی بلا ناغہ مسلسل روزے رکھتے
پہلے جانا.عید کے دن اور ایام تشریق یعنی ۱۱- ۱۲ اور ۱۳ ذو الحجہ کو روزہ رکھنا سخت منع ہے لیے
رمضان کے روزے
ماہ رمضان اور اس کی فضیلت :.ماہ رمضان
کو خدا تعالیٰ نے ایک اہم اور بابرکت
مہینہ قرار دیا ہے.قرآن کریم کے نزول کا آغازہ اسی مہینہ سے ہوا.فرمایا :-
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِى أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدَى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَتِ
مِنَ الهُدى وَالْفُرْقَانِ " له
رمضان
کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس کے بارہ میں قرآن کریم نازل کیا گیا ہے وہ قرآن جو تمام
انسانوں کے لئے ہدایت بنا کر بھیجا گیا ہے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے :
JAY
له : - بخاری کتاب الصوم من : : فتاوی عالمگیری و در مختار بحوالہ بہار شریعیت مثه جلده: ۳: بقره مث :
Page 279
وو
إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فُتِحَتْ ابْوَابُ الْجَنَّةِ وَخُلِقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ وَمُقَدَتِ
الشَّيَاطِينُ له
اس با برکت مہینہ میں جنت کے دروازے سے کھل جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند
کر دیئے جاتے ہیں.شیاطین قید کر دیئے جاتے ہیں.یعنی.یہ مبارک مہینہ فضل الہی اور رحمت خداوندی کو جذب کرنے کا ایک بابرکت مہینہ ہے
اس مہینہ میں خصوصا اس کے آخری عشرہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت دعائیں مانگا کرتے
اور بہت زیادہ صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے.روزہ کیس پر فرض ہے
رمضان کے روز سے ہر بالغ عاقل تندرست مقیم مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہیں.مسافر
اور بیمار کو یہ رعایت ہے کہ وہ دوسرے ایام میں ان روزوں کو پورا کرلیں.جو اس ماہ میں ان
سے رہ گئے ہیں مستقل بیمار جنہیں صحت یاب ہونے کی کبھی امید نہ ہو یا ایسے کمزورونا توان
ضعیف جنہیں بعد میں بھی روزہ رکھنے کی طاقت نہ ملے.اسی طرح ایسی مرضعہ اور حاملہ جو تسلسل
کے ساتھ ان عوارض سے دو چار رہتی ہے.ایسے معذور حسب توفیق روزوں کے بدلہ میں فدیہ
ادا کریں.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :
منْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى
الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينِ " له
تم میں سے جو شخص مریض ہو یا سفر میں ہو تو اُسے اور دنوں میں تعداد پوری کرنی
ہوگی اور اُن لوگوں پر جو اس یعنی روزہ کی طاقت نہ رکھتے ہوں بطور فدیہ ایک مسکین
کا کھانا دینا بشرط استطاعت واجبہ
روزہ کرے رکھنا چاہیئے
رمضان کے روزوں کے لئے حکم ہے کہ لا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الهِلَالَ “جب تک ماه
رمضان کا چاند نظر نہ آجائے روزہ نہ رکھو.یہ رویت نظری بھی ہو سکتی ہے اور علمی بھی.رویت علمی کی دو صورتیں ہیں.ایک یہ کہ شعبان کے پورے تیس دن گزر چکے ہوں یا باتفاق علماء
ه : - بخاری کتاب الصوم ص ۲۵ :
:- بقره : ۱۸۵ :
Page 280
۴۷۴
اقت ایسا حسابی کھنڈر بنا لیا جائے جس میں چاند نکلنے کا پورا پورا حساب ہو اور غلطی کا امکان نہ
رہے.ریڈیو وغیرہ کے ذریعہ چاند نکلنے کی خبر شرعا معتبر ہے اس کے مطابق حسب فیصلہ ارباب علم و
اقتدار عمل کیا جائے گا.لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ جگہ جہاں چاند دیکھا گیا ہے اور جہاں خبر
پہنچی ہے دونوں کا افق اور مطلع ایک ہو ورنہ یہ خبر قابل عمل نہ ہوگی.یعنی اگر دونوں علاقوں کا فاصلہ
بہت زیادہ ہو جیسے برطانیہ اور پاکستان تو یہ خبر ان علاقوں کے لحاظ سے ایک دوسرے کے
لئے قابل عمل نہ ہوگی.اگر مطلع صاف نہ ہو ابر یا گہری دھند ہو تو رمضان کے چاند کی رویت کے ثبوت کے لئے
ایک معتبر عادل آدمی کی گواہی قبول کی جاسکتی ہے لیکن افطار اور عید الفطر منانے کے فیصلہ کے
لئے کم از کم دو عادل آدمیوں کی گواہی ضروری ہے.اے
روزہ کے لئے نیت ضروری ہے
جس شخص کا روزہ رکھنے کا ارادہ ہو اسے روزہ رکھنے کی نیت ضرور کرنی چاہیئے.آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا ہے :-
مَنْ لَمْ يَجْمَعِ الصَّوْمَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ »
جو صبح سے پہلے روزہ کی نیت نہ کرے اس کا کوئی روزہ نہیں.نیت کرنے کے لئے کوئی معین
الفاظ زبان سے ادا کر نے ضروری نہیں.نیت دراصل دل کے اس ارادے کا نام ہے کہ وہ کس لئے کھانا پینا چھوڑ رہا ہے.نفلی روزہ میں دن کے وقت دوپہر سے پہلے پہلے دبشر طیکہ نیت کرنے کے وقت تک کچھ
کھایا پیانہ ہو ، روزہ کی نیت کر سکتے ہیں.اسی طرح اگر کوئی عذر ہو مثلا رمضان کا چاند نکلنے کی
خبر طلوع فجر کے بعد ملی ہو اور ابھی کچھ کھایا پیا نہ ہو تو اس وقت روزہ کی نیت کر سکتے ہیں اور ایسے
شخص کا اس دن کا روزہ ہو جائے گا.روزہ رکھنے اور افطار کرنے کا وقت
كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ
ن : تحریزی کتاب الصوم باب الصوم بالشهادة ص : : - ترندي كتاب العلوم باب لا صيام لمن لم يغيره من الليل صلاة
Page 281
۲۷۵
مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ آتِمُّوا القِيَامَ إِلَى اللَّيْلِ -
کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہیں صبح کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے الگ نظر
آنے لگے.اس کے بعد صبح سے رات تک روزوں
کی تکمیل کرو.حدیث میں ہے :-
إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ وَادْبَرَ النَّهَارُ وَغَابَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ افْطَرَ
الصَّائم - له
جب دن چلا جائے رات آجائے.سورج ڈوب جائے تو روزہ افطار کر لو.آدھی رات کو اُٹھ کر سحری کھا لینا یا بغیر سحری کھائے روزہ رکھنا مسنون نہیں.اصل برکت
اور اتباع سنت اس میں ہے کہ طلوع فجر سے تھوڑا پہلے انسان کھائی ہے.اس کے بعد روزہ کی
نیت کر سے.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا یہی طریق تھا.حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے :-
تسَحْرُ وا نَانَ فِي السَّحُورِ بَرَكَة له
سحری کھایا کرو کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے.موجودہ زمانہ میں طلوع فجر یعنی صبح صادق کا اندازہ بذریعہ گھڑی اس طرح لگایا جا سکتا ہے
کہ کسی دن سورج نکلنے کا وقت نوٹ کر لیا جائے اور اسے قریباً ایک گھنٹہ بائیس منٹ پہلے
تک سحری کھائی جائے.حدیث میں ہے :- تسخَرْنَا ثُمَّ قُمْنَا إِلَى الصَّلوة - له
کہ سحری کھانے کے بعد ہم نمازہ کے لئے کھڑے ہو جاتے.سحری کھانے اور نماز فجر میں تقریبا پچاس آیتیں تلاوت کرنے کے برابر وقفہ ہوتا تھا.ایک اور حدیث میں ہے :-
كُنتُ أَتَسَخَرُ فِي اهْلِى ثُمَّ تَكُونُ سُرْعَةٌ بِي أَنْ أَدْرِكَ صَلوةَ
الْفَجْرِ مَعَ رَسُولِ اللهِ - شم
ه بقره : ۱۸۸ : ۵۳ : ترمذی باب اذا قبل الليل الخصب : ه: بخاری باب بركة السحور ما :
ه ترندی کتاب الصوم باب تا خیر السحور منه : شه بخاری کتاب مواقيت الصلواة باب وقت الفجر به بخاري في تجميل الحوم
Page 282
کہ سحری کھانے کے بعد نماز فجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پانے کے لئے
ہمیں جلدی ہوتی تھی.وقت افطار
غروب آفتاب کے ایک دو منٹ بعد روزہ افطار کر لینا چاہیئے.غیر معمولی تاخیر درست نہیں.حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے :-
لا يزال النَّاسُ بِخَيْرِ مَا عَجَلُوا الفِطرَ.که به وزہ افطار کرنے میں جب تک لوگ جلدی کرتے رہیں گے اس وقت تک خیر و برکت
بھلائی اور بہتری حاصل کرتے رہیں گے.ایک اور حدیث ہے :-
عن الى أذنى قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ
فَلَمَّا غَابَتِ الشَّمْسُ قَالَ لِرَجُلَ اَنْزِلْ نَاجُدَحْ لَنَا فَقَالَ يَا
رَسُولَ اللهِ لَوْ أَمْسَيْتَ قَالَ انْزِلُ نا جدَحَ لَنَا قَالَ إِنَّ عَلَيْنَا
نِهَارًا قَالَ اَنْزِلْ فَا جُدَحَ لَنَا فَنَزَلَ فَجَدَحَ لَهُ فَشَرِبَ ثُمَّ
قَالَ إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ قَدْ اقْبَلَ مِنْ هُهُنَا وَرَشَارَ بِيَدِهِ
نَحْوَ الْمَشْرِقِ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ.حضرت ابی اوفی بیان کرتے ہیں کہ ایک سفر میں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا
غروب آفتاب کے بعد حضور نے ایک شخص کو افطاری لانے کا ارشاد فرمایا.اس شخص نے
عرض کی حضور ڈرا تاریکی ہو لینے دیں.آپ نے فرمایا کہ افطاری لاؤ.اس شخص نے
پھر عرض کی کہ حضور ابھی تو روشنی ہے.حضور نے فرمایا.افطاری لاؤ.وہ شخص افطاری
لایا.آپ نے روزہ افطار کرنے کے بعد فرمایا کہ جب تم غروب آفتاب کے بعد
مشرق کی طرف سے اندھیرا اُٹھتے دیکھو تو افطار کر لیا کرو.مغرب کی طرف نہ دیکھتے
رہو کہ اس طرف روشنی غائب ہوئی ہے یا نہیں.۲۶۳
مد بخاری باب تعجیل الافطار :: مسلم کتاب الصوم باب بيان وقت انقضاء الصوم صاله :
Page 283
روزہ کسی چیز سے افطار کرنا چاہیئے
روزه کھجور ، دودھ ، سادہ پانی سے کھولنا مسنون ہے
ہے.إذَا افْطَرَ اَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرُ عَلَى تُمَرِنَانٌ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ
مَاءٍ فَإِنَّهُ طَهُورٌ له
جب روزہ افطار کرنا ہو تو کھجور سے افطار کرے کیونکہ اس میں برکت ہے.اگریہ
میتر نہ ہو تو پانی سے روزہ افطار کرلے کیونکہ یہ بہت پاک چیز ہے.افطار کرتے وقت یہ دُعا پڑھے :-
اللهم إنّي لكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ افْطَرْتُ - له
اسے اللہ میں نے تیری خاطر ہی روزہ رکھا ہے اور تیرے ہی رزق سے میں نے افطارہ
کیا ہے.بعد افطار یہ کہے :.ہو
ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَتِ الْعُرُوقُ وَشَبَتِ الْأَجْرُ إِن شَاءَ اللهُ له
پیاس دُور ہو گئی اور رگیں تروتازہ ہو گئیں اور اجر ثابت ہو گیا اگر خُدا تعالیٰ چاہیے.کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرانا بہت ثواب کا کام ہے.روزہ افطار کرانے والے کوڑزہ دار
جتنا ثواب ملتا ہے.مَن فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ غَيْرَ انَّهُ لَا يَنْقُصُ مِنْ
اجرِ الصَّائم شي
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو روزہ افطار کرائے اُسے روزہ رکھنے
کے برابر ثواب ملے گا لیکن اس سے روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی.نواقضی روزه
عمد ا کھانے پینے اور جماع یعنی جنسی تعلق قائم کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے.اینیما کرانے،
ه : - ترندی باب ما يستحب عليه الافطار مست ہے.ابوداؤدنيا القول عند الانظار ص ٣٢ :
- ابوداود کتاب الصوم باب القول عند الافطار ۳ : ۱۲ - ترندي كتاب الصوم باب فضل من فطر صائما ما.
Page 284
۲۷۸
ٹیکہ لگوانے اور جان بوجھ کر قے کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے.حدیث ہے :-
مَنْ ذَرَعَهُ الْقَنَى وَهُوَ صَائِمُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءُ وَ مَنِ اسْتَقَاءَ
عَمَدًا فَلْيَقْضِ له
اگر کسی روزہ دار کو بے اختیار قے آجائے تو اس پر روزہ کی قضاء نہیں.لیکن جو
روزہ دار جان بوجھ کر تھے کر سے تو وہ روزہ قضاء کرے.رمضان کا روزہ محمداً توڑنے والے کے لئے اس روزہ کی قضاء کے علاوہ کفارہ دیعنی بطور
سزا، ساٹھ روز سے متواتر رکھنا بھی واجب ہے.اگر روزہ رکھنے کی استطاعت نہ ہو تو اپنی حیثیت کے مطابق ساٹھ غریبوں کو کھانا کھلانا اکٹھے
بٹھا کر یا متفرق طور پر یا ایک غریب کو ہی ساٹھ دن کے کھانے کا راشن دے دینا یا اس کی قیمت ادا
کرنا کافی ہے.اگر کھانا کھلانے کی بھی استطاعت نہ ہو تو اُسے اللہ تعالی کے رحم اور اس کے فضل پر بھروسہ
کرنا چاہیئے.تے
اگر کوئی غلطی سے رمضان کا روزہ کھول سے تو کوئی گناہ نہیں لیکن اس روزہ کی قضاء ضروری ہے.اگر روزہ دار ہونے کی صورت میں عورت کے خاص ایام شروع ہو جائیں یا بچہ پیدا ہو تو روزہ ختم ہو جائے گا
البتہ بعد میں ان ایام کے روزوں کی قضاء واجب ہے.وہ امور جرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا
اگر کوئی بھول کر کچھ کھایی سے تو اس کا روزہ علی حالہ باقی رہے گا اور کسی قسم کا نقص اس کے بعدہ
میں واقع نہیں ہوگا.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے :-
إِذَا نَسَى أَحَدُكُمْ فَا كُل أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا اطْعَمَهُ
الله وسَقَاه - که
اگر کوئی شخص بھول کر روزہ میں کھاپی ہے تو اسکی اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا.وہ اپنا روزہ
له : - ترندی باب من استقاء عمدًا من : سه - بخاری باب اذا جامع في رمضان ولم يكن
له شى...الخ : : - بخاری کتاب الصوم باب الصائم اذا اكل او شرب ناسيا ما ب
ص۲۵
1
Page 285
۲۷۹
پورا کر سے کیونکہ اس کو اللہ تعالی کھلا پلا رہا ہے.اگر بلا اختیار حلق میں یا پیٹ میں دھواں گردو غبار مکھی مچھر کلی کرتے وقت چند قطرے
پانی چلا جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا.اسی طرح کان میں پانی جانے یا دوا ڈالنے.بلغم نگلنے.بلا اختیار
ئے آنے.آنکھ میں دوا ڈلوانے نکسیر پھوٹنے.دانت سے خون جاری ہونے.چیچک کا ٹیکہ لگواتے
مسواک یا برش کرنے.خوشبو سونگھنے.ناک میں دوا چڑھانے.سریا داڑھی پر تیل لگا نے.بچے یا
بیوی کا بوسہ لینے.دن کے وقت سوتے میں احتلام ہو جانے یا سحری کے وقت غسل جنابت نہ کر سکتے
کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا.دن کے وقت عورت سرمہ لگا سکتی ہے.مرد کے بارے میں آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے :-
لا تنتَحِلُ بِالنِّهَارِ وَانتَ صَائِمٌ وَالتَحِل لَيْلاً - له
اسے عزیزہ بحالت روزہ دن کو شرمہ نہ نگا البتہ رات کو لگا سکتے ہو.حضرت مسیح موعود علیہ السّلام فرماتے ہیں : -
دن کو سرمہ لگانے کی ضرورت ہی کیا ہے رات کو لگائے " سے
روزہ نہ رکھنے والے
رمضان کا روزہ بلا عذر یا معمولی معمولی باتوں کو عذر بنا کر ترک کرنا درست نہیں ایسے لوگ جو
جان بوجھ کر روزہ نہیں رکھتے ان کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے : -
" مَنْ اَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْضَةٍ وَلَا مَرَضِ فَلَا
يَقْضِيْهِ صِيَامُ الخِرِ كُلِهِ وَلَوْ صَامَ الدَّهَرَ له
جو شخص بلا عذر رمضان کا ایک روزہ بھی ترک کرتا ہے وہ شخص اگر بعد میں تمام عمر بھی
اس روزہ کے بدلہ میں روزے رکھے تو بھی بدلہ نہیں چکا سکے گا.اور اس غلطی
کا تدارک نہیں ہو سکے گا.: - قَالَ الْحَسَنُ رَابِأْسَ بِالسَّعُوطِ لِلصَّامِينَ لَمْ يَصِلُ إِلى حَلْقِهم.بخاری باب قول النِي إِذَا تَونَ.الجوه
٥٣: - ثَلْتُ رَيُفْطِرْنَ الصَّائِمَ الْحَجَامَةُ وَالْقَى وَالِاحْتِلاهُ - (ترندى مث )
186
4%
ه بسند دارمی با الکحل للصائم عنا : - بدر باشه : مستند دارمی باب من اخطر و با من میان مستحيد انها
Page 286
دو
حضرت خلیفتہ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے :-
" میرے نزدیک ایسے لوگ بھی ہیں جو روزہ کو بالکل معمولی حکم تصور کرتے ہیں
اور چھوٹی چھوٹی وجہ کی بناء پر روزہ ترک کر دیتے ہیں بلکہ اس خیال سے بھی کہ ہم
بیمار ہو جائیں گے روزہ چھوڑ دیتے ہیں حالانکہ یہ کوئی عذر نہیں کہ آدمی خیال کہ سے
یں بیمار ہو جاؤں
گا......روزہ ایسی حالت میں ہی ترک کیا جا سکتا ہے کہ آدمی
بیمار ہو اور وہ بیماری بھی اس قسم کی ہو کہ اس میں روزہ رکھنا مضر ہو......وہ بیماری کہ جس پر روزہ کا کوئی اثر نہیں پڑتا اس کی وجہ سے روزہ ترک کرنا جائز
نہیں ہوگا اے
فتاوی
سوال ہے: اگر کسی ملک میں ۲۹ تاریخ کو مطلع ابر آلود ہونے کی وجہ سے چاند نظر نہ آئے اور کسی
اور ملک سے ریڈیو پر یہ اطلاع مل جائے کہ چاند نظر آگیا ہے تو کیا اول الذکر ملک کے
لوگ اس رویت کی اتباع کر سکتے ہیں ؟
جواب : اگر افق اور مطلع میں اتحاد ہو تو ایک علاقہ کے لوگ دوسرے علاقہ کی رومیت پر روزہ افطار
کر سکتے ہیں اور عید منا سکتے ہیں.رمضان شروع ہونے کا بھی یہی حکم ہے.دُور کے ممالک
جن کا افق یعنی مطلع ایک نہیں اس حکم کے ماتحت نہیں آتے.اسی طرح بعض اوقات
حکومتوں کا اختلاف بھی اثر انداز ہوتا ہے.جیسا کہ آگے تفصیلی ذکر آتا ہے.علامہ ابن رشد اپنی مشہور کتاب بدایۃ المجتہد میں لکھتے ہیں :-
هَلْ يَجِبُ عَلَى أَهْلِ بَلَدٍ مَّا اذَا لَمْ يَرُوهُ أَن يَأْخُذُوا فِي ذَالِكَ
بِرُويَةِ بَلَدٍ آخَرَ امْ يكُلِّ بَلَدِرُؤْيَةٌ فِيهِ خِلَانُ.......رَوَى
المدنيونَ عَنْ مَالِكِ انَّ الرُّؤْيَةَ لَا تَلْزِمُ بِالْخَبَرِ عَبْدَ غَيْرِ اهْلِ
الْبَلَدِ الَّذِى وَقَعَتْ فِيهِ الرُّؤْيَة إِلَّا أَنْ يَكُونَ الإِمَامُ يَحْمِلُ النَّاسَ
عَلَى ذَلِكَ.....وَاجْمَعُوْا أَنَّهُ لا يُرَا عِى ذَلِكَ فِي الْبُلْدَانِ النَّائِيَةِ
الأندلس وَالْحِجَازِ.......اَمَّا انَّ الْبِلَادَ إِذَا لَمْ تَخْتَلِفْ مُطَالِعُهَا
كُلَّ الْاِخْتِلَافِ نَيَجِبُ أَنْ يُعْمَلَ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ لِأَنَّهَا فِي قِيَاسِ الْأُفُقِ
: -
ل الفضل دراپریل ۹۲۵ له :
Page 287
۲۸۱
الواحده
یعنی کیا یہ ضروری ہے کہ اگر ایک علاقہ میں چاند دیکھا گیا ہو تو دوسرے علاقہ والے جنہوں
نے چاند نہیں دیکھا اس علاقہ کے لوگوں پر اعتبار کر کے ان کی پیروی کریں یا یہ ضروری
نہیں ؟..اس سوال کے مختلف جواب دیئے گئے ہیں.امام ابو حنیفہ اور امام شافعی
وغیرہ کہتے ہیں کہ اگر افق ایک ہے تو پیروی ضروری ہے اور اہل مدینہ کی روایت
کے مطابق امام مالک کا مسلک یہ ہے کہ ایک افق کی صورت میں بھی پیروی ضروری
نہیں.ہاں اگر اس علاقہ کی مسلمان حکومت ان کی رویت کے مطابق فیصلہ کرے اور
اتباع کا حکم دے تو پھر پیروی کرنی چاہیے.اور اگر دونوں علاقے بہت دُور دُور
واقع ہوں.اس طرح کہ دونوں کے مطالع بکلی مختلف ہوں جیسے جہاز اور اندلس کے
مطلع رافق) میں فرق ہے تو پھر ایک علاقہ کے لوگوں کا چاند دیکھنا دوسرے علاقہ
والوں پہ اثر اندازہ نہیں ہو سکتا اور نہ ہی اس کی پیروی ضروری ہے.ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت کریب نے ایک دفعہ کسی کام کے لئے شام گئے
وہاں انہوں نے جمعرات کو رمضان کا چاند دیکھا.جب وہ مدینہ واپس آئے تو حضرت
ابن عباس نے ان سے پوچھا کہ کب چاند دیکھا تھا.انہوں نے کہا جمعرات کو.اور
وہاں کے لوگوں نے اس کے مطابق روزے رکھے ہیں.حضرت ابن عباس نے فرمایا
کہ ہم نے ہفتہ کی رات کو چاند دیکھا تھا اور ہم اس کے مطابق اپنے روز سے پورے
کریں گے.اس پر حضرت کریب نے کہا کیا حاکم وقت حضرت معاویہ کا چاند دیکھنا آپ
کے لئے کافی نہیں.حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ حضورصلی الہ علیہ وسلم کا ایسا ہی حکم ہے ہے
اس حدیث سے یہی مترشح ہوتا ہ ہے کہ دُور کے ممالک اختلاف مطلع کی بناء پر ایک دوسرے
کی رویت کے لازماً پابند نہیں ہیں.تاہم اگر دونوں علاقوں کے مطالع میں کوئی خاص فرق نہ ہو تو اتحاد
افق کی وجہ سے ایک علاقہ کی رویت کا دوسرے علاقہ والوں کو اعتبار کرنا چاہیئے اور اسے تسلیم کر کے
بداية المجتهد كتاب الصيام من جلدا : : تريدي كتاب الصوم باب لكل اصل بلد رويتهم
۱۵ ترندی کتاب الصیا در باب لكل اهل بلد د ويتهم من جلد اول :
شده جلد اول
Page 288
اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے لیے
چاند دیکھنے کی جو خبر مصدقہ اور صحیح ہو خواہ معتبر یر یڈیو کے ذریعہ ملے.جماعت احمدیہ کے
نزدیک (معتبر اور جائز العمل ہے.چاند دیکھنے کا غیر طبعی طریق
سوال : - ہوائی جہاز میں بیٹھے کہ اوپر جانے والوں کو اگر رمضان یا عید کا چاند نظر آجائے لیکن
زمین پر ظاہری آنکھ سے کسی کو نظر نہ آئے تو کیا روزہ یا عید ہو جائے گی یا نہیں ؟.جواب :.اس طرح چاند دیکھنے کا شرعا اعتبار نہیں کیونکہ یہ تکلف ہے.چاند کا دیکھنا وہی معتبر
ہے جو عام آنکھ سے بغیر کسی تکلف یا سائنسی آلہ کی مدد کے دیکھا جائے مطلع ابر آلود ہونے
کی صورت میں ماہ رمضان کے روزہ کے لئے ایک معتبر آدمی کی یہ گواہی کہ اُس نے چاند دیکھا
ہے جائز التسلیم ہوگی اور عید منانے کے لئے دو معتبر آدمیوں کی گواہی ضروری ہوگی.تاہم
اس قسم کے معاملات میں جماعت مسلمین کے مرکزی نظام کو آخری فیصلہ کا اختیار حاصل ہے.سوال: - حدیث میں آتا ہے کہ چاند دیکھ کر روزہ افطار کرو.کیا اگر چاند سورج ڈوبنے سے پہلے نظر
آجائے تو روزہ افطار کر لینا چاہئیے ؟
جواب ہے :.اس حدیث افطار کے معنے یہ ہیں کہ اگر بعد دوپہر سورج ڈوبنے سے پہلے شوال کا چاند
نظر آجائے تولوگ اگلے دن عید الفطر منائیں اور روزہ نہ رکھیں.یہ نہیں کہ چاند دیکھتے ہی
روزہ کھول دیں بالکل اسی طرح جس طرح منو مُوالِدُ وَيَتِ کے معنی ہیں کہ چاند نظر آنے
پر اگلے دن سے روزے رکھنے شروع
کر دو یہ نہیں کہ جو نہی چاند نظر آئے اُسی وقت سے
روزه شروع کردو.کیونکہ روزہ کا وقت خواہ وہ روزہ فرض ہو یا نفلی طلوع فجر سے لیکر
غروب آفتاب تک ہے اسے کم وقت کا روزہ صحیح روزہ نہیں ہوگا.قرآن پاک کی آیت ثُمَّ أَتِمُّوا القِيَامَ إِلَى اللَّيْلِ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
سنّتِ متواترہ اسی حقیقت کو ثابت کرتی ہے درہا یہ خیال کو سورج ڈوبنے سے پہلے جو
چاند نظر آجاتا ہے وہ دراصل ایک دن پہلے کا ہے اور یہ دن گویا روزے کا ہے ہی نہیں.تو اصولاً یہ خیال درست نہیں کیونکہ بعض صورتوں میں چاند پہلی کا ہوتے ہوئے بھی غروب
آفتاب سے کچھ دیر قبل نظر آسکتا ہے ہاں بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر چاند اس دن
ترندی باب ماجاء في الصور بالشهادة شب، ابن ماجه كتاب الصوم باب في الشهادة على روبيته الهلال ما:
Page 289
۲۸۳
دوپہر سے پہلے نظر آئے تو پھر چاند دیکھتے ہی روزہ توڑ دینا چاہیئے.کیونکہ یہ در اصل یکم شوال
یعنی عید کا دن ہوگا.۲۹ یا ۳۰ ر رمضان کا دن نہ ہو گا.حضرت عمر نے عتبہ بن فرقد کو ایک خط میں لکھا :-
۱- اگر چاند صبح کو نظر آئے تو روزہ توڑ دو کیونکہ وہ کل کا ہے اور اگر چاند آخر دن میں نظر
آئے تو اس دن کا روزہ پورا کر لو کیونکہ وہ آنے والی کل کا ہے.۲ - کچھ نئے چاند بڑے ہوتے ہیں.اس لئے اگر تم دن میں چاند دیکھو تو اس وقت تک
روزہ نہ توڑو جب تک دو مسلمان گواہی نہ دیں کہ انہوں نے گذشتہ رات چاند
دیکھا تھا.اے
علامہ ابن رشد اپنی مشہور کتاب "بداية المجتهد" میں لکھتے ہیں :-
قَالَ أَبُو يُوسُفَ مِنْ أَصْحَابِ رَبِي حَنِيفَةَ وَالثَّوْرِي وَابْنُ جِيْبِ
مِنْ اَصْحَابِ مَالِكِ إِذَا رُؤى الهِلَالُ قَبْلَ الزَّوَالِ فَهُوَ لَيْلَةِ
المَاضِيَةِ وَإِنْ رُوَى بَعْدَ الزَّوَالِ فَهُوَ لِلْآتِيَةِ - وَرَوَى
الثَّورِيُّ انَّهُ بَلَغَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ إِنَّ قَوْ مَا رَأَوُا الْهِلَالَ
بعْدَ الزَّوَالِ فَا فَطَرُوا فَكَتَبَ إِلَيْهِمْ يَلُومُهُمْ وَقَالَ إِذَا
ر ANALOGOLE LALENT نِهَارًا قَبْلَ الزَّوَالِ فَافَطِرُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ
بَعْدَ الزَّوَالِ فَلَا تَفْطِرُوا " :
یعنی حنفیوں میں سے امام ابو یوسف اور مالکیوں میں سے ابن حبیب نیز امام
ثوری کا مسلک یہ ہے کہ اگر شوال کا چاند دو پہر سے پہلے نظر آجائے تو روزہ
فوراً توڑ دینا چاہیے کیونکہ یہ چاند آنے والی رات کا نہیں بلکہ گذشتہ رات کا ہے
اور یہ دن یکم شوال کا گذر رہا ہے.۳۲۵
ے:.حضرت عمر کے سرکاری خطوط از خورشید احمد فاروقی ص۲۳ بحوالہ کنز العمال منقول اثر مصنف ابن ابی
140
- بداية المجتهد كتاب الصوم ما :
شیبه قلمی من :
: بعض ماہرین ہیت کی رائے یہ ہے کہ یہ صورت درست نہیں ہے کیونکہ پہلی کا چاند دوپہر سے پہلے نظر
نہیں آسکتا لیکن محترم مرزا عبدالحق صاحب صدر تدوین فقہ کمیٹی کا بیان ہے کہ شہداء میں خود انہوں نے دس بجے چاند دیکھا :
-
Page 290
حضرت عمرہ کے زمانہ میں ایک علاقہ کے لوگوں نے دوپہر کے بعد چاند دیکھا اور
اسی وقت روز سے کھول لئے.حضرت عمر کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے
انہیں تنبیہ فرمائی اور لکھا کہ اگر چاند دو پہر سے پہلے دیکھا جائے تو پھر روزہ توڑ
دینا چاہیے.لیکن اگر دو پہر کے بعد نظر آئے تو پھر روزہ مکمل کرنا چاہیئے اور غروب
آفتاب کے بعد کھولنا چاہیے.سوال :.امریکہ کے ایک نو مسلم نے لکھا ” اس وقت میں روزہ سے
رکھ رہا ہوں کو مجھے مجھے علم نہیں کہ
رمضان کس تاریخ کو شروع ہوا.میں نے روز سے گذشتہ ماہ کی اور تاریخ کو شروع کئے تھے
اور اس ماہ کی ۲۰ر تاریخ تک رکھوں گا.حضرت خلیفہ المسیح الثانی نہ نے اس کے جواب میں فرمایا : -
رمضان المبارک در مئی سے ۲ جون تک رہا اور سر جون کو عید ہوئی لیکن جس
شخص کو علم نہ ہو کہ رمضان کب شروع ہوا کب ختم ہوا، وہ جس وقت بھی روزے
رکھے خدا تعالٰی کے نزدیک وہی مقبول ہیں کیونکہ ہمارا خدا ہمارے علم کے مطابق
ہم سے مطالبہ کرتا ہے.اگر وہ اپنے علم کے مطابق ہم سے مطالبہ کرے تو دنیا کا کوئی
انسان بھی نجات نہ پائے " لے
روزہ اور نیت
سوال : کیا روزہ کے لئے نیت ضروری ہے ؟
جواب :.حضور نے فرمایا :-
" روزے کے لئے نیت ضروری ہے.بغیر
نیت کا ثواب نہیں نیت دل کے ارادے
کا نام ہے.افق مشرق پر سیاہ دھاری سے سفید دھار ی شمالاً جنوباً ظاہر ہونے تک
کھانا پینا جائز ہے.اگر اپنی طرف سے احتیاط ہو اور بعد میں کوئی کہے کہ اس وقت
سفیدی ظاہر ہو گئی تھی تو روزہ ہو جاتا ہے.نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانا.کھانے اور نماز فجر میں ۵۰ آیت پڑھنے تک وقفہ ہوتا تھا " ہے
ایک شخص صبح سے شام تک بغیر کچھ کھائے پیئے سویا رہا یا کسی کام میں ایسا منہمک ہوا کہ کھانے
پینے کی ہوش ہی نہ رہی تو اس شخص کے اس فاقہ کو روزہ سمجھنا درست نہ ہوگا.کیونکہ روزہ رکھنے
ل : الفضل ۲۸ جولائی ۶۹۵۴
له الفضل ۲۸ جولائی ۱۹۱۲م :
Page 291
۲۸۵
کی اس کی نیت ہی نہ تھی اور نہ ہی اس کا یہ فاقہ اس ارادہ سے تھا کہ اس کا روزہ ہے.سوال : اگر بوقت سحری روزہ کی نیت نہ تھی لیکن - ایا 1 بجے دن کے روزہ کا ارادہ کر لیا تو کیا اس
کا روزہ ہو جائے گا ؟
جوا ہے :.روزہ کی نیست طلوع فجر سے پہلے کی جانی چاہئیے.البتہ اگر کوئی عذر ہو مثلاً اسے علم نہیں
ہو سکا کہ آج سے رمضان شروع ہے یا سویا رہا صبح بیدار ہونے پر پتہ چلا کہ آج تو روزہ
ہے یا کوئی اور اسی قسم کا عذر ہے تو وہ دوپہر سے پہلے پہلے اس دن کے روزہ کی نیت کر سکتا
ہے.بشرطیکہ اس نے طلوع فجر کے بعد سے کچھ کھایا پیا نہ ہو.حضرت ابن عمر سے روایت ہے :-
عن ابن عمر عن حفصة عن النبي صلى الله عليهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ
قَالَ مَنْ لَمْ يَجْمَعِ القِيَا مَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَا مَلَهُ ثواه الخمسة.یعنی.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا.روزہ صرف اُسی شخص کا ہے جس نے
پختہ.فجر سے پہلے پختہ عزم کے ساتھ روزہ کی نیت کرلی ہو.لیکن اس کے ساتھ ہی ایک اور حدیث ہے کہ :-
إِنَّهُ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْخُلُ عَلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ فَيَقُولُ
هَلْ مِنْ غَدَاءٍ فَانَ قَالُو الأَ قَالَ فَإِنِّي صَائِم له
یعنی حضور صلی اللہ علیہ و سلم بعض دفعہ گھر تشریف لاتے اور دریافت فرماتے کہ
اور ناشتہ کے لئے کوئی چیز ہے ؟ اگر یہ خواب ملتا کہ کچھ نہیں تو آپ فرماتے اچھا
آج میں روزہ رکھ لیتا ہوں.اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر فجر سے پہلے نیت کرنے میں کوئی عذر ہو تو دن کے وقت
بھی روزے کی نیست کی جاسکتی ہے.گو حضور علیہ السلام کے یہ روز سے نقلی تھے.اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ ایک بارد و پہر سے پہلے خبر ملی کہ کل رمضان کا چاند
مدینہ کی کسی مضافاتی بستی میں دیکھ لیا گیا تھا.اس پر حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے صبح سے
ه: نیل الاوطار باب وجوب الفنيته من الليل ما ، ترندی کتاب العلوم باب لا صيام لمن لم يعتزم من الليل ما
ہے: مسلم کتاب الصوم باب جواز صوم النافلة بينة من النهار ما :
Page 292
۲۸۶
کچھ نہیں کھایا وہ روزہ کی نیت کرنے اور جنسی کچھ کھا پی لیا ہے وہ بعد میں اس روزہ کی
قضاء کرے یا لے
سوال (3) ایک شخص نفلی روزہ کی نیت کرتا ہے لیکن سحری کھانے سے رہ جاتا ہے تو کیا وہ روزہ
رکھے ؟
(ب) رمضان میں رات کو بیمار تھا.صبح سحری کے وقت طبیعت سنبھل گئی تو کیا وہ روزہ رکھے؟
(ج)، فرض روزہ کے لئے سحری نہ کھا سکے تو کیا روزہ رکھے؟
جواب ، (( سحری کھانا مسنون ہے ضروری اور واجب نہیں اس لئے اگر کوئی سحری نہیں کھا
سکا تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے یہ نہیں کہ اس کا روزہ ہی نہیں ہوتا.(ب) اگر سحری کے وقت طبیعت اچھی ہو تو روزہ رکھنا چاہئیے.رات سے روزہ کی نیت
ہونے کے معنے یہ ہیں کہ طلوع فجر سے پہلے پہلے روزہ رکھنے کا ارادہ کرے.سوال :.کیا سحری کھانا ضروری ہے ؟
جواب : - سحری کھائے بغیر روزہ رکھنے میں برکت نہیں.ویسے ضرورت اور عذر کی صورت میں
سحری کھائے بغیر بھی روزہ رکھنا جائز ہے.حضرت انسخ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا :-
تَسَخَرُوا فَانَ فِي السَّحُوْرِ بَرَكَة - له
سحری کھایا کرو کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے.ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر درود بھیجتے
ہیں.سے
سفیدی میں نیت روزه
سوال : ایک شخص کا سوال پیش ہوا کہ میں مکان کے اندر بیٹھا ہوا تھا اور میرا یقین تھا کہ ہنوز روزہ
رکھنے کا وقت ہے اور میں نے کچھ کھا کر روزے کی نیت کی مگر بعد میں ایک دوسرے شخص سے
ابوداود كتاب الصيام باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان ص ۳۳ : ۱۵۲- بخاری کتاب الصوم باب
16
بركة السحور من غير ايجاب الخصه : -:- اوجز المسالک شرح موطا امام مالک مٹ جلد ۳ ہے
Page 293
۲۸۷
معلوم ہوا کہ اس وقت سفیدی ظاہر ہو گئی تھی اب یکیں کیا کروں ؟
جواب: - حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسی حالت میں اس کا روزہ ہو گیا دوبارہ
رکھنے کی حاجت نہیں کیونکہ اپنی طرف سے اُس نے احتیاط کی اور نیت میں فرق نہیں ؟ لے
سوال : - قرآن کریم کی آیت تم اتموا القيامَ إِلَى : نَّيْلِ میں آنیل سے از روئے
لخت کیا مراد ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ کی افطاری کے بارہ میں کیا عمل تھا؟
جوا ہے :.لغت میں لیل کے معنی ہیں " من مغرب الشمس الى طلوع الشمس يعنى سوج
کے غروب ہونے سے لے کر اُس کے طلوع ہونے تک کے وقت کولیل کہتے ہیں لیکن سنت
متواترہ اور امت کے اجتماعی عمل سے یہ امر
ظاہر ہے کہ آیت مذکورہ میں ساری رات مراد
نہیں بلکہ اس کا کوئی حصہ ہے جس میں روزہ کھولنا ہے.اب ہم اس حصہ کی تعین کے لئے
قرآنی محاورہ پر غور کرتے ہیں تو یہ رات کا آغاز یعنی سورج کے غروب ہونے کا وقت بنتا ہے
کیونکہ الیٰ کا مفہوم یہ ہے کہ روزہ رات آنے تک رکھتا ہے اور اس کے شروع ہوتے ہی
افطار کر لینا ہے چنانچہ احادیث بھی اسی مفہوم کی تائید کرتی ہیں.بخاری اور سلم کی حدیث
ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: " إِذَا اقْبَلَ اللَّيْلُ وَادْبَرَ بنَهَارُ وَغَابَتِ
الشَّمْسُ فَقَدْ فَطَرَ القائم ہے کہ جونہی مشرق سے رات آئے اور مغرب کی طرف
دن جائے یعنی سورج افق میں غائب ہو جائے تو اُسی وقت روزہ دار کو روزہ کھول لینا
چاہیئے.اسی طرح فرمایا " لا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرِ مَا عَقَلُوْ الْفِطْرَ ۳.جب تک
لوگ روزہ جلدی افطار کرتے رہیں گے اُس وقت تک بہتری اور بھلائی اُن کے ساتھ رہے
گی.ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ حضور علیہ اسلام نے فرمایا یہود و نصاری روزہ افطار کر نے میں
دیر کرتے ہیں مسلمانوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے.اے
ترندی کی حدیث ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم روزہ جلدی افطار کرنے کا خاص اہتمام فرمایا
ه بدر ۱۳ فروری شای فتادی مسیح موعود ص : ه: - بخاری کتاب الصوم باب متى يجيل نطر الصائم ،
مسلم باب انا وقت انقضاء الصور الخاصه - ترندی کتاب الصوم من : که بخاری باب
تعجیل الافطار ما
عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر
مسلم
عجلوا الفطر فان الیهو دیر خرون را این ماجه کتاب الصوم باب ماجاء في تعجيل الافطار صا :
Page 294
کرتے تھے.اے
YNA
پس یہی سنت متواتر ہے اور اہل سنت والجماعت کے تمام علماء کا اسی کے مطابق عمل ہے.سفر سے روزہ کی ممانعت کی وضاحت
1 - حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے سفر میں روزہ رکھنے کو حکم عدولی قرار دیا ہے.چنانچہ حضور
فرماتے ہیں :.مریض اور سافر اگر روزہ رکھیں تو ان پر حکم عدولی کا فتوی لازم آئے گا "
حضور علیہ السلام کا یہ فیصلہ آیت قرآنی فعدل من ايام اخر پر مبنی ہے اور احادیث نبوی
کے مجموعی مفہوم سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کی حالت میں
رمضان میں روزہ رکھنے والوں کو عصا " قرار دیا ہے.جن احادیث سے رخصت معلوم ہوتی
ہے امام زہری نے ان احادیث کو پہلے کی قرار دیا ہے.چنانچہ صحیح مسلم کی تصریح ہے لیے
۲ - حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے باہر سے آنے والے احمدیوں کے لئے قادیان کو وطن ثانی قرار دیا
ہے اس لئے وہ وہاں قیام کے دوران میں رکھ سکتے ہیں اور اگر نہ رکھیں تب بھی جائز ہے.۳ - وطن ثانی کی طرف سفر بھی سفر ہی ہے.اس لئے روزہ رکھنا جائز نہیں.حضرت مسیح موعود علیہ السلام
نے افطاری کے وقت سے پہلے قادیان آنے والے روزہ داروں کا روزہ کھلوا دیا تھا..وہ تمام لوگ جن کی ڈیوٹی ہی سفر سے متعلق ہو جیسے ریلوے گارڈ - ڈرائیور - پائیلٹ سفری ایجینٹ
دیہاتی ہرکارے وغیرہ مقیم کے حکم میں ہوں گے او رمضان کے روزے رکھیں گے لیے
حضرت اقدس علیہ السّلام نے سفر میں روزہ کے حکم کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا :-
" اگر ریل کا سفر ہو کوئی تکلیف کسی قسم کی نہ ہو تو رکھ لے ورنہ خدا تعالیٰ کی رخصت
سے فائدہ اُٹھائے یہ تو
: - ترندی باب تعجیل الافطا رصد : ۱۵ - سورة البقرة آیت نمبر ۱۸۵ :
: - مسلم کتاب الصوم باب جواز الصوم والفطر الخ ص ٣ : قال الزهرى وكان الفطر آخر الأمرين
و نما یؤخذ من امر رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالآخر فالآخر.وسلم ) :
:- فیصد مجلس افتاء ۲۴ مورخہ ۲۶ فروری شار : له : - الحکم ۲۳ دسمبر نت شالله :
"
Page 295
۲۸۹
سوال ہے :.اگر کسی روزہ دار کو سفر کرنے کی ضرورت پیش آئے تو کیا وہ روزہ توڑ سکتا ہے ؟
جواب :.رمضان کے دنوں میں حتی الوسع سفر سے بچنا چاہیے.اور ضرورت کے وقت ہی سفر پر
جانا چاہیے.کونسا سفر ضروری ہے اس کا فیصلہ خود سفر کرنے والے کی صوابدید پر ہے اور
وہی اللہ تعالٰی کے سامنے جوابدہ ہے کوئی دوسرا اس کے متعلق فیصلہ نہیں کر سکتا.باقی سفر
کوئی سا ہو جب تک وہ جاری ہے اس میں روزہ نہیں رکھنا چاہیئے.روزہ رکھ کر سفر شروع کرنا
سید نا حضرت خلیفہ المسیح الثانی فرماتے تھے:.سفر کے متعلق میرا عقیدہ اور خیال یہی ہے ممکن ہے بعض فقہاء کو اس سے
اختلاف ہو کہ جو سفر سحری کے بعد شروع ہو کہ شام کو ختم ہو جائے وہ روزہ کے لحاظ
سے سفر نہیں.سفر میں روزہ رکھنے سے شریعیت روکتی ہے.مگر روزہ میں سفر کرنے
سے نہیں روکتی.پس جو سفر روزہ رکھنے کے بعد شروع ہو کر افطاری سے پہلے ختم
ہو جائے وہ روزہ کے لحاظ سے سفر نہیں.روزہ میں سفر ہے سفر میں روزہ نہیں 1
سوال : بحالت سفر روزہ رکھا جا سکتا ہے یا نہیں.نیز کتنے میں تک کا سفر ہو جس میں روزہ نہیں
رکھنا چاہیے ؟
جواب :.سفر میں رمضان کا روزہ نہیں رکھنا چاہئیے.البتہ رمضان کے احترام میں یہ سر عام کھانے
پینے سے اختراز کرنا ستحسن ہے.سفر اور اس کی مسافت کی کوئی شرعی صدا در تعریف مقرر نہیں
اسے انسان
کی اپنی تمیز اور قوت فیصلہ پر رہنے دیا گیا ہے لیے
سفر میں روزہ سے کی چار صورتیں ہو سکتی ہیں :-
اگر سفر جاری ہو یعنی پیدل یا سواری پر.اور چلتا چلا جارہا ہو تو روزہ نہ رکھا جائے.کیونکہ اس
صورت میں روزہ چھوڑنا ضروری ہے..اگر سفر کے دوران کسی جگہ رات کو ٹھہرنا ہے اور سہولت میسر ہے تو روزہ رکھا جاسکتا ہے یعنی روزہ
رکھنے اور نہ رکھتے دونوں کی اجازت ہے.جبکہ دن بھر وہاں قیام ہے.له الفضل میر ے :.سفر کی مزید تفصیل کے لئے دیکھیں باب قصر الصلواۃ
Page 296
۲۹۰.سحری کھانے کے بعد گھر سے سفر شروع ہو اور افطاری سے پہلے پہلے سفر ختم ہو جائے یعنی گھر
واپس آجانے کا ظن غالب ہو تو روزہ رکھ سکتا ہے.۴ - اگر کسی جگہ پندرہ دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنا ہے تو وہاں سحری کا انتظام کیا جائے اور روزہ
رکھا جائے.بیمار اور مسافر
حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السّلام نے فرمایا کہ :
” جو شخص مریض اور مسافر ہونے کی حالت میں ماہ صیام میں روزہ رکھتا ہے وہ خدا تعالٰی
کے صریح حکم کی نافرمانی کرتا ہے.خُدا تعالیٰ نے صاف فرما دیا ہے کہ بیمار اور مسافر روزہ
نہ رکھے.مرض سے صحت پانے اور سفر کے ختم ہونے کے بعد روزے رکھے خُدا کے
اس حکم پر عمل کرنا چاہیئے کیونکہ نجات فضل سے ہے اور اپنے اعمال کا زور دکھا کر
حکم
کوئی شخص نجات حاصل نہیں کر سکتا.خدا تعالٰی نے یہ نہیں فرمایا کہ مرض تھوڑی ہویا
بہت اور سفر چھوٹا ہو یا لمبابلکہ حکم عام ہے اور اس پر عمل کرنا چاہیئے.مریض اور
مسافر اگر روزہ رکھیں گے تو ان پر حکم عدولی کا فتوی لازم آئے گا یا لے
روزہ رکھنے کی عمر
حضرت خلیفہ ایسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا :-
کئی ہیں جو چھوٹے بچوں سے بھی روزہ رکھواتے ہیں.حالانکہ ہر ایک فرض اور حکم کے
لئے الگ الگ حدیں اور الگ الگ وقت ہوتا ہے.ہمارے نزدیک بعض احکام کا زمان چاری
سال
کی عمر سے شروع ہو جاتا ہے اور بعض ایسے ہیں جن کا زمانہ سات سال سے بارہ
سال تک ہے اور بعض ایسے ہیں جن کا زمانہ ۱۵ یا ۸ سال کی عمر سے شروع ہوتا ہے میرے
نزدیک روزوں کا حکم ۱۵ سے ۸ سال تک کی عمر کے بچے پر عائد ہوتا ہے اور یہی بلوغت
کی حد ہے.ہ سال کی عمر سے روزہ رکھنے کی عادت ڈالنی چاہیئے اور ۱۸ سال کی عمر
میں روز سے فرض سمجھنے چاہئیں.مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے تھے ہمیں بھی روزہ رکھنے کا
شوق ہوتا تھا.مگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نہیں روزہ نہیں رکھنے دیتے تھے اور بجائے اس
ه بدر ، اکتوبر شاه :
14
Page 297
۲۹۱
کے کہ ہمیں روزہ رکھنے کے متعلق کسی قسم کی تحریک کرنا پسند کریں ہمیشہ ہم پر رعب ڈالتے
تھے.تو بچوں کی صحت کو قائم رکھنے اور اُن کی قوت کو بڑھانے کے لئے روزہ رکھنے سے
انہیں روکنا چاہیے.اس کے بعد جب ان کا وہ زمانہ آجائے جب وہ اپنی قوت کو
پہنچ جائیں جو ہ اسال کی عمر کا زمانہ ہے تو پھر ان سے روزے رکھوائے جائیں اور وہ
بھی آہستگی کے ساتھ.پہلے سال جتنے رکھیں دوسر سے سال ان سے کچھ زیادہ اور
تیسرے سال اسی زیادہ رکھوائے جائیں.اس طرح بتدریج ان کو روزہ کا عادی بنایا
جائے کالے
بوڑھا جس کی قومی مضمحل ہو چکے ہیں اور روزہ اسے زندگی کے باقی اشغال سے محروم
کر دیتا ہے اس کے لئے روزہ رکھتا نی کی نہیں.پھر وہ بچہ جس کے قومی نشود نما پا ر ہے
ہیں اور آئندہ ۵۰ - ۶۰ سال کے لئے طاقت کا ذخیرہ جمع کر رہے ہیں اس کے لئے
بھی روزہ رکھنا نی کی نہیں ہو سکتا مگر جس میں طاقت ہے اور جو رمضان کا مخاطب
ہے وہ اگر روزہ نہیں رکھتا تو گناہ کا مرتکب ہے" کے
مرضعہ حاملہ بچہ اور طالب علم
" قرآن میں صرف بیمار اور مسافر کے لئے روزہ نہ رکھنے کی وضاحت ہے.دودھ پلانے
والی عورت اور حاملہ کے لئے کوئی ایسا حکم نہیں مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بیمار
کی حد میں رکھا ہے.اسی طرح وہ بچے بھی بیمار کی حد میں ہیں جن کے اجسام ابھی نشو و نما پا
رہے ہیں یا کمزور صحت کے ساتھ جو امتحان کی تیاری میں بھی مصروف ہیں.اُن دنوں اُن
کے دماغ پر اس قدر بوجھ ہوتا ہے کہ بعض پاگل ہو جاتے ہیں.کئی ایک کی صحت خراب
ہو جاتی ہے.پس اسکی کیا فائدہ ہے کہ ایک بار روزہ رکھ لیا اور پھر ہمیشہ کے لئے
محروم ہو گئے.تے
سوال :.طالب علم جو امتحان کی تیاری میں مصروف ہے اس کے لئے روزہ رکھنے کی کیا ہدایت ہے؟
جوا ہے :.روزہ کی وجہ سے روزمرہ کی مصروفیات کو ترک کرنے کا ہمیں حکم نہیں دیا گیا اس لئے
روزمرہ کے کام کی وجہ سے اگر ایک انسان کے لئے روزہ ناقابل برداشت ہے تو وہ مریضی
کے حکم میں ہے لیکن اس بارہ میں کلیتہ وہ اپنے اقدام کا خود ذمہ وار ہو گا اور اس کی اسکی
1 - الفضل را پیل له : الفصل ۲ فروری ۱۹۳۳ : ۳: - الفضل جلد ۱۸ نمبر ۸ است گره :
Page 298
۲۹۳
نیت اور حالت کے مطابق اللہ تعالٰی سلوک کہ سے گا.گویا اپنے حالات کے بارہ میں فیصلہ
دینے میں انسان آپ مفتی ہے.جو شخص روزہ رکھنے سے بیمار ہو جاتا ہے خواہ وہ پہلے بیمار نہ ہو اس کے لئے روزہ
معاف ہے.اگر اس کی حالت ہمیشہ ایسی رہتی ہو تو کبھی اس پر روزہ واجیبت نہ ہوگا.اور
اگر کسی موسم میں ایسی حالت ہو تو دوسرے وقت میں رکھ ہے.ہاں تقوی نے کام سے
کو خود سوچ ہے کہ صرف قدر نہ ہو بلکہ حقیقی بیمار ہوگا اے
سوال :.بعض اوقات رمضان ایسے موسم میں آتا ہے کہ کاشتکاروں سے جبکہ کام کی کثرت ہوتی ہے.مثلاً
تخم ریزی کرنا یا فصل کاٹنا ہے.اسی طرح مزدور جین کا گذارہ مزدوری پر ہے ان سب سے روزہ
نہیں رکھا جاتا.ان کی نسبت کیا ارشاد ہے ؟
جواب: - حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا :-
" إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ.یہ لوگ اپنی حالتوں کو مخفی رکھتے ہیں.سرشخص تقوی و
طہارت سے اپنی حالت سوچ نے اگر کوئی اپنی جگہ مزدور رکھ سکتا ہے تو ایسا کو ہے ورنہ
مریض کے حکم میں ہے پھر جب میسر ہو رکھ لے اور عَلَی الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ کی نسبت
فرمایا کہ معنے یہ ہیں کہ جو طاقت نہیں رکھتے " ہے
ایک دوست نے حضرت صاحب سے ذیا بیطس کی بیماری میں روزہ کیسے متعلق دریافت
کیا.اس کے جواب میں آپ نے فرمایا :-
بیماری میں روزہ جائز نہیں اور ذیا بیطس کے لئے تو بہت ہی مضر ہے " سے
بعض پرانی بیماریاں
بعض بیماریاں ایسی بھی ہوتی ہیں جن میں انسان سارے کام کر لیتا ہے مثلاً پرانی بیماریاں ہیں.اگن
میں انسان سب کام کرتا رہتا ہے ایسا شخص بیمار نہیں سمجھا جاتا.حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے ایک دفعہ یہ تو پوچھا گیا کہ کیا اس ملازم کا سفر شمار کیا جائے گا
جو ملازم ہونے کی وجہ سے سفر کرتا ہے.آپ نے فرمایا :-
اوراس کا سفر سفر نہیں گیتا جا سکتا.اس کا سفر تو ملانہ مت کا ایک حصہ ہے.اسی طرح
بعض ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جن میں انسان سارے کام کرتا رہتا ہے.فوجیوں میں بھی ایسے
له الفضل -۲۲ مئی ۱۹۲۳ : ۵- پلاک ۲ ستمبر نشده : الفضل 10 جولائی شامار :
ه :
Page 299
۲۹۳
ہوتے ہیں جو ان بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں مگر وہ بسیار سے کام کرتے رہتے ہیں.چند دن
پیچش ہو جاتی ہے مگر اس وجہ سے وہ ہمیشہ کے لئے کام کرنا چھوڑ نہیں دیتے.پس اگر
دوسرے کاموں کے لئے وقت نکل آتا ہے، تو کیا وجہ ہے کہ ایسا مریض بروز ہے نہ رکھ سکے
اس قسم کے بہانے محض اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ ایسے لوگ دراصل روزہ رکھنے کے خلاف
ہوتے ہیں.بیشک یہ قرآنی حکم ہے کہ سفر کی حالت میں اور ایسی طرح بیماری کی حالت میں
روزہ سے نہیں رکھنے چاہئیں.اور ہم اس پر زور دیتے ہیں تا قرآنی حکم کی بہتک نہ ہو مگر
اس بہانہ سے فائدہ اُٹھا کہ جو لوگ روزہ رکھ سکتے ہیں اور پھر وہ روزہ نہیں رکھتے یا
ان سے کچھ روز سے رہ گئے ہوں اور وہ کوشش کرتے تو انہیں پور ا کر سکتے تھے لیکن ان کو
پورا کرنے کی کوشش نہیں کرتے تو وہ ایسے ہی گنہگار ہیں جس طرح وہ گنہ گار ہے جو
بلا عذر را امضان کے روزہ سے نہیں رکھتا.اس لیئے ہر احمدی کو چاہیئے کہ جتنے روز سے اس
نے غفلت یا کسی شرعی عذیہ کی وجہ سے نہیں رکھے وہ انہیں بعد میں پورا کیا ہے.بعض فقہا کا خیال ہے کہ پچھلے سال کے چھوٹے ہوئے روز سے دوسرے سال نہیں
رکھ سکتے لیے لیکن میرے نزدیک اگر کوئی لاعلمی کی وجہ سے روز سے نہیں رکھ سکا توں علمی معاف
ہو سکتی ہے.ہاں اگر اسے بھی دیدہ دانستہ روز سے نہیں رکھتے تو پھر قضاء نہیں.جیسے جان بوجھ
کہ چھوڑی ہوئی نمازہ کی قضاء نہیں لیکن اگر انہی بھول کر روزے نہیں رکھے یا اجتہادی
غلطی کی بناء پر اس نے روزے نہیں رکھتے تو میرے نزدیک وہ دوبارہ رکھ سکتا ہے" سے
فدیہ توفیق روزہ کا موجب ہے
حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں :-
ایک بار میرے دل میں آیا کہ یہ فدیہ کن لئے مقربہ ہے تو معلوم ہوا ہے اس لئے کہ اس
سے روزہ کی توفیق ملتی ہے.خُدا ہی کی ذات ہے جو توفیق عطا کرتی ہے اور ہر شئی خداہی سے
طلب کرنی چاہیئے وہ قادر مطلق ہے وہ اگر چاہیے تو ایک مدقوق کو بھی طاقت روزہ عطا
کر سکتا ہے.اس لئے مناسب ہے کہ ایسا انسان جو دیکھے کہ روزہ سے محروم رہا جاتا
ہوں تو ڈھاکہ سے کہ الہی یہ تیرا ایک مبارک مہینہ ہے میں اسے محروم رہا جاتا ہوں اور
کیا معلوم کہ آئندہ سال رہوں یا نہ رہوں یا ان فوت شده روزوں کو ادا کر سکوں یانہ کر سکوں
ها بداية المجتهد :
الفضل ۱۶ راگست شته ؟
یا
Page 300
۲۹۴
اس لئے اس سے توفیق طلب کرے مجھے یقین ہے کہ ایسے قلب کو خُدا طاقت بخشے گا
اگر خدا چاہتا تو دوسری امتوں کی طرح اس امت میں بھی کوئی قید نہ رکھتا مگر اس نے قیدین
بھلائی کے لئے رکھی ہیں.میرے نزدیک اصل یہی ہے کہ جب انسان صدق اور کمال
اخلاص سے باری تعالی میں عرض کرتا ہے کہ اس مہینے میں مجھے محروم نہ رکھ تو خدا سے
محروم نہیں رکھتا اور اسی حالت میں اگر رمضان میں بیمار ہو جائے تو یہ بیماری اس کے حق
میں رحمت ہو جاتی ہے کیونکہ ہر کام کا مدار نیت پر ہے مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے وجود
سے اپنے آپ کو خدا تعالی کی راہ میں دلاورثابت کرے.جو شخص کہ روزہ سے محروم رہتا
ہے مگر اس کے دل میں یہ نیت درد دل سے تھی کہ کاش میں تندرست ہوتا اور روزہ رکھتا
اس کا دل اس بات کے لئے گریاں ہے تو فرشتے اس کے لئے روزے رکھیں گے بشرطیکہ
وہ بہانہ جو نہ ہو تو خُدا تعالیٰ ہرگز اُسے ثواب سے محروم نہ رکھے گا.یہ ایک باریک امر
ہے.اگر کسی شخص پر اپنے نفس کے کسل کی وجہ سے روزہ گراں ہے اور وہ اپنے خیال
میں گمان کرتا ہے کہ میں بیمار ہوں اور میری صحت ایسی ہے کہ اگر ایک وقت نہ کھاؤں
تو فلاں فلاں عوارض لاحق ہوں گے اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا تو ایسا آدمی جو خُدائی نعمت کو
خود اپنے اوپر گراں گمان کرتا ہے کب اس ثواب کا مستحق ہوگا.ہاں وہ شخص جس کا دل
اس بات سے خوش ہے کہ رمضان آگیا اور اس کا منتظر ہی تھا کہ آد سے اور روزہ
رکھوں اور پھر وہ بوجہ بیماری کے نہیں رکھ سکا تو وہ آسمان پر روزہ سے محروم نہیں ہے اس
دنیا میں بہت لوگ بہا نہ جو ہیں اور وہ خیال کرتے ہیں کہ ہم اہل دنیا کو دھوکا دے لیتے
ہیں ویسے ہی خُدا کو فریب دیتے ہیں لیکن وہ خُدا کے نزدیک صحیح نہیں ہے.تکلف کا
باب بہت وسیع ہے اگر انسان چاہے تو اس کی رُو سے ساری عمر کو بیٹھ کر ہی نما زپڑھتا
رہے.اور رمضان کے روز سے بالکل نہ رکھے مگر خدا اس کی نیت اور ارادہ کو جانتا ہے
جو صدق اور اخلاص رکھتا ہے خُدا جانتا ہے کہ اس کے دل میں درد ہے اور خُدا اُسے صل
ثواب سے بھی زیادہ دیتا ہے کیونکہ در دل ایک قابل قدر شئے ہے“ لے
يدية
اگر انسان مریض ہو خواہ وہ مرض لاحق ہو یا ایسی حالت میں ہوجس میں روزہ رکھا یقیناً مریضی بنا دیگا.: قنادی احمدیه ما
140
Page 301
۲۹۵
جیسے حالہ یا دودھ پلانے والی عورت یا ایسا بوڑھا شخص جس کی قومی میں انحطاط شروع
ہو چکا ہے یا پھر اتنا چھوٹا بچہ جس کے قومی نشو و نما پا رہے ہیں تو ا سے روزہ نہیں رکھنا
چاہیئے اور ایسے شخص کو اگر آسودگی حاصل ہو تو ایک آدمی کا کھانا کسی کو دیدینا چاہیئے
اور اگر یہ طاقت نہ ہو تو نہ ہی ایسے شخص کی نیت ہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کے روزہ
کے برابر ہے.اگر روک عارضی ہو اور بعد میں وہ دور ہو جائے تو خواہ فدیہ دیا ہو یا نہ دیا ہو روزہ
بہر حال رکھنا ہوگا کیونکہ فدیہ دے دینے سے روزہ اپنی ذات میں ساقط نہیں ہو جاتا
بلکہ یہ تو محض اس بات کا بدلہ ہے کہ ان دنوں میں باقی مسلمانوں کے ساتھ مل کر اس عبادت
کو ادا نہیں کر سکتا یا اس بات کا شکرانہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ عبادت کرنے کی توفیق
بخشی ہے کیونکہ روزہ رکھ کر جو فدیہ دیتا ہے وہ زیادہ ثواب کا مستحق ہوتا ہے کیونکہ روزہ
رکھنے کی توفیق پاتے پہ خدا تعالیٰ کا شکرانہ ادا کرتا ہے اور جو روزہ رکھنے سے معذور
ہو وہ اپنے اس عذر کی وجہ سے بطور کفارہ دیتا ہے.آگے یہ عذر دو قسم کے ہوتے ہیں عارضی اور مستقل.ان دونوں حالتوں میں فدیہ دینا
چاہیئے.پھر جب عذر دُور ہو جائے تو روزہ بھی رکھنا چاہیئے.غرضیکہ خواہ کوئی قدیر
بھی دیدے لیکن سال دو سال تین سال جب بھی صحت اجازت دے اسے حسب
استطاعت روزہ رکھنا ہوگا.سوائے اس صورت کے کہ پہلے مرض عارضی تھا اور صحت
ہونے کے بعد وہ ارادہ کرتا رہا کہ آج رکھتا ہوں کل رکھتا ہوں کہ اس دوران میں اس
کی صحت مستقل طور پر خراب ہو گئی تو ایسی صورت میں فدیہ کفایت کرے گا ؟ بے
سوال : فدیہ رمضان کس پر واجب ہے کیا بوڑھا.ضعیف.دائم المریض.حاملہ - مرضعہ وغیرہ
جو آئندہ رمضان تک گنتی پوری کرنے کی توفیق نہ رکھتے ہوں صرف وہی فدیہ دیں یادہ شخص
بھی جو وقتی طور پر بیمار ہو کر چند روزسے چھوڑ دینے پر مجبور ہو جاتا ہے اور رمضان کے بعد
تندرست ہو کہ گنتی پوری کرنے کی توقع رکھتا ہے اور توفیق پاتا ہے.نیز فدیہ کی مقدار کیا ہے؟
جوا ہے :- عام ہدایت یہ ہے کہ انسان روز سے بھی رکھے اور اگر استطاعت ہو تو فدیہ بھی دے.روزوں
کا رکھنا فرض ہوگا اور فدیہ کا اداکرنا سنت باقی رمضان کے روزوں کا فدیہ اس شخص کے لئے ضروری
نہیں جو وقتی طور پر بیمار ہونے کی وجہ سے چند روزے چھوڑ دینے پر مجبور ہو گیا ہو.سوائے اسکے
الفضل ۱۰ اگست ۱۹۲۵ :
Page 302
۲۹۶
کہ وہ ان روزوں کی قضاء سے پہلے ہی اپنے مولیٰ کو پیارا ہو جائے.اس صورت میں اس کے
ورت پر لازم ہو گا کیا وہ اس کی طرف سے ان روزوں کا فدیہ ادا کریں یا اتنے روز سے رکھیں جو
اُس کے رہ گئے تھے.رمضان کے روزوں کا لازمی فدیہ صرف ایسے ذی استطاعت لوگوں کے لئے ہے جن کے
متعلق یہ توقع نہ ہو کہ مستقبل قریب میں ان روزوں کی قضاء کر سکیں گے جیسے بوڑھا ضعیف
ہے یا کوئی دائم المرض ہے یا حامہ اور مرضعہ ہے.علامه ابن رشد بداية المجتھد میں لکھتے ہیں
امَّا حُكْمُ الْمُسَافِرِ إِذَا افْطَرَ فَهُوَ الْقَضَاءُ بِاتِّفَاقِ وَكَذَلِكَ الْمَرِيضُ
لِقَوْلِهِ تَعَالَى " فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرُ لَهُ
صاحب اوجز المسالک لکھتے ہیں :-
الْعَامِلُ وَالْمُرْضِع إِذَا افْطَرَنَا مَاذَا عَلَيْهِمَا وَهَذِهِ الْمَسْئَلَةُ
لِلْعُلَمَاءِ فِيْهَا ارْبَعَةٌ مَذَا هِبَ اَحَدُهَا إِنَّهَا يُطْعِمَانِ وَلَا قَصَاءَ
عَلَيْهِمَا وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ ابْنِ عَجَاسَ "
" وَفِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنِ
المُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلوةِ وَعَنِ الْعَامِلِ وَالْمُرْضِعِ الصَّوْمَ له
قدید کی مقدار کیا ہے اس بارہ میں اصولی ہدایت یہ ہے کہ :
مِن أوسَطِ مَا تُطْعِمُونَ اهْلِيكُمْ فه.پس اس اصول کو مد نظر رکھا جائے.البتہ امام ابو حنیفہ نے اس کا اندازہ گندم کے لحاظ سے
نصف صاع یعنی پونے دوسیر کے قریب بیان کیا ہے.اور یہ ایک فوت شدہ روزہ کا فدیہ
له - بداية المجتهد جلد اول م۲ : ۱۹ - اوجز المسالک شرح موطا مالک من جلدم ، بداية المجتهد:
ه - ترندی کتاب الصوم باب الرخصة في الافطار للحبلى والمرضع طب : المائدة آيت ٩٠+
شو صارع : ناپنے کا پیمانہ جس کا حجم ۱، ۲۶ لیٹر کے مساوی ہوتا ہے جو مساوی ہے ۲۷۰ مکعب سنٹی میٹر کے.اس حجم کے پیما
میں اہ، نوگرام پانی آتا ہے جو سادی ہے ۲ سیرہ نے تولہ ماشہ ۸۳ و ارتی کے لیکناس حجم کے پیمانہ میں گیہوں کی جو مقدار آتی وہ ساری ہے
۷۳ ۲۱ گرام ۲۰ سیر ۲ تولہ ۳ ماشہ اوہ رتی.لہذا گیہوں کی مقدار کے اعتبار سے ایک صاع ۲۹ ۷۳۰ ۲۱ گرام ، میری ۲ تولہ ۶ ماشد
اوره رتی.نیز ایک صاع ٥ رطل.ایک دوسر تحقیق کے مطابق ایک صاع - ۲ سیر ۲۹ تولہ ۶ ماشه - اسلام کا نظام محاصل میشه :
Page 303
ہوگا جو دو وقت کے کھانے کے لئے کفایت کرے گا.یہ ضروری نہیں کہ فدیہ کسی ایسے غریب کو ہی دیا جائے جو روزہ رکھتا ہو.اصل مقصد مستحق
نا دار کو کھانا کھلانا ہے خواہ وہ خود روزہ رکھ سکتا ہو یا کسی عذر کی بناء پر نہ رکھ سکتا ہو اسی
طرح فدیہ اُسی پر واجب ہے جو ادا کرنے کی استطاعت رکھتا ہو ورنہ ایک غیر مستطیع کے لئے
ندامت - توبہ استغفار - دعا.ذکر الہی اور خدمت دین کا استلزام کفایت کرے گا.دائمی مسافر اور مریض فدیہ دے سکتے ہیں
حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے مورخہ ۳۰ اکتوبر نشاستہ کو فرمایا :-
درجن بیماروں اور مسافروں کو اُمید نہیں کہ کبھی پھر روزہ رکھنے کا موقع مل سکے مثلاً
ایک بہت بوڑھا ضعیف انسان یا ایک کمزور حاملہ عورت جو دیکھتی ہے کہ بعد وضع حمل
سبب بچے کے دودھ پلانے کے وہ پھر معذور ہو جائے گی اور سال پھر اسی طرح گذر
جائے گا.ایسے شخص کے واسطے جائز ہو سکتا ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں کیونکہ وہ روزہ
رکھ ہی نہیں سکتے اور فدیہ دیں.ندیہ صرف شیخ خانی یا اس جیسوں کے واسطے ہو سکتا ہے جو روزہ کی طاقت کبھی
بھی نہیں رکھتے.باقی اور کسی کے واسطے جائز نہیں کہ صرف فدیہ دے کر روزے کے
رکھنے سے معذور سمجھا جاسکے.عوام کے واسطے جو صحت پا کر روزہ رکھنے کے قابل ہو
جاتے ہیں صرف فدیہ کا خیال کرنا اباحت کا دروازہ کھولنا ہے" سے
سوال :.روزے رکھنے کے لئے جسے بطور فدیہ پیسے دینے ہیں اُسے پہلے سے کسی اور نے بھی فدیہ
کے پیسے دے رکھے ہیں اصل حکم کیا ہے ؟
ہوا ہے :.یہ خیال غلط ہے کہ کسی کو پیسے دے کہ روز سے رکھوائے جائیں.اصل حکم یہ ہے کہ اگر کوئی
شخص بوجه معذوری روز سے نہیں رکھ سکتا تو وہ ہر روزہ کے بدلہ کسی مسکین محتاج کو دو وقت
کا کھانا کھلائے یا اس کھانے کی قیمت ادا کرے جس مستحق کو فدیہ دیا گیا ہے اس کے لئے یہ ضروری
نہیں کہ اسکی بدلہ میں وہ اس کی طرف سے روزہ بھی رکھے اگر وہ نادار خود بیما رہے ضعیف العمر
ہے یا نا بالغ ہے تو وہ روزہ نہیں رکھے گا.لیکن اس کے باوجود اپنی محتاجی کے پیش نظر فدیہ
لینے کا مستحق ہوگا.البتہ جس مستحق کو فدیہ دیا گیا اگر وہ روز سے رکھتا ہے تو یہ امر مزید ثواب
ل : فتاوی احمدیہ مشا :
Page 304
۲۹۸
کا موجب یقینا ہے لیکن یہ شرط لازم نہیں کہ اس کے بغیر فدیہ ادا ہی نہ ہو.جان بوجھ کر روزه تورونیا
جو شخص جان بوجھ کہ روزہ رکھ کر توڑد سے وہ سخت گنہگار ہے.ایسے شخص پر بغرض تو بہ کفارہ
واجب ہوگا.یعنی پے در پے اُسے ساٹھ روزے رکھنے پڑیں گے یا ساٹھ مسکینوں کو اپنی حیثیت کے مطابق
کھانا کھلانا پڑے گا یا ہر مسکین کو دوسیر گندم یا اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی.توبہ کے سلسلہ میں اصل
چیز حقیقی ندامت ہے جو دل کی گہرائیوں میں پیدا ہوتی ہے اگر یہ کیفیت انسان کے اندر پیدا ہو جائے
لیکن اس کو ساٹھ روزے رکھنے یا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانے کی استطاعت نہ ہو تو اسے اللہ تعالیٰ
کے رحم اور اس کے فضل پر بھروسہ کرنا چاہیئے.اس صورت میں استغفار ہی اس کے لئے کافی
ہو گا.حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور دہائی دینے لگا.یا
حضرت میں ہلاک ہو گیا.حضور نے فرمایا کہ کس نے تجھے ہلاک کیا ہے ؟
اس نے عرض کی کہ حضور روزہ کی حالت میں میں اپنی بیوی کے پاس چلا گیا ہوں.حضور نے
فرمایا کیا تو غلام آزاد کر سکتا ہے ؟ اس نے کہا نہیں.پھر حضورا نے پوچھا ساٹھ روز سے مسلسل رکھ
سکتا ہے ؟ اس نے عرض کی حضور نہیں اگر ایسا ہو سکتا اور شہوانی جوشن روک سکتا تو یہ غلطی ہی سرزد
کیوں ہوتی.حضور نے فرمایا تو پھر ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا دو.ار نے کہا غربت ایسا کرنے سے
مانع ہے.حضور نے فرمایا تو پھر بیٹھو.اتنے میں کوئی شخص ایک ٹوکری کھجوروں کی لے آیا.آپ نے
فرمایا اٹھا ہے.اور اسے مسکینوں
کو کھلا دے.ٹوکری لے کر عرض کرنے لگا.مجھ سے زیادہ اور کون
غریب ہوگا.مدینہ بھر میں سب سے زیادہ محتاج ہوں.حضور اس کی اس لجاجت پر کھلکھلا کر ہنس پڑے
اور فرمایا جاؤ اپنے اہل و عیال کو ہی کھلا دو.ماہ رمضان میں ایک شخص جس کا روزہ نہیں اپنی ایسی بیوی سے ہمبستری کرتا ہے جس کا
روزہ ہے اور وہ خاوند کو بتا بھی دیتی ہے.کیا حکم ہے ؟
جوا ہے :.بیوی کا روزہ ٹوٹ جائے گا.البتہ اگر وہ رضامند نہ تھی تو اس پر بطور سزا کوئی کفارہ نہیں
ہاں وہ یہ روزہ دوبارہ رکھے گی اور اگر وہ بھی رضا مند تھی تو وہ کفارہ ادا کر ے ساٹھ روز سے
رکھے یا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے اور خاوند تو گنہگار ہے ہی اسے تو بہ و استغفا را در آئندہ
کے لئے اس حرکت سے اجتناب کا پختہ عہد کرنا چاہیئے.اور کفارہ بھی.وال :
Page 305
۲۹۹
سوال : اگر کوئی شخص شدت پیاس کی وجہ سے روزہ توڑد سے تو کیا اس کو کفارہ ادا کر نا پڑیگا ؟
جوا ہے : اگر کوئی شدت پیاس سے مجبور ہو کر روزہ توڑد سے تو اس کے لئے اس روزہ کی قضاء ضروری
ہے.البتہ ایسی صورت میں کفارہ فدیہ وغیرہ ضروری نہیں ہو گا.کفارہ صرف ایسی صورت
میں ضروری ہوتا ہے جب کہ انسان بغیر کسی قدر اور مجبوری کے جان بوجھ کر روزہ توڑدے.ایسی حالت میں اس کے لئے ضروری ہوگا کہ وہ اس غلطی کا کفارہ ادا کر سے یعنی دو ماہ کے متواتہ
روز سے رکھنے اور اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو پھر ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے
سوال : خیال تھا کہ آج عید ہے.صبح آٹھ بجے ناشتہ کر کے عید گاہ گیا تو معلوم ہوا کہ عید تو
کل ہے.میں نے اسی وقت سے روزہ کی نیت کر لی اور پھر شام تک کچھ نہ کھایا.کیا میرا
روزہ ہو گیا ؟
جوا ہے :.روزے کے لئے ضروری ہے کہ طلوع فجر سے لے کہ غروب آفتاب تک کچھ نہ کھایا جائے
اور نیت روزے کی ہو.چونکہ دن کے وقت یہ سمجھتے ہوئے کھانا کھا لیا گیا کہ آج روزہ نہیں اسلئے
گناہ تو نہیں ہوا لیکن روزہ بھی نہیں ہوا اس لئے اس کی قضاء ضروری ہے.سوال :.کیا روزہ دار کے لئے ہر قسم کا ٹیکہ کروانا منع ہے.حکومت کی طرف سے جو ٹیکے لگوائے
جاتے ہیں کیا روزہ دار وہ کروا سکتا ہے ؟
جوا ہے :.جب اللہ تعالیٰ نے یہ رحمایت دی ہے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہے تو وہ رمضان کے بعد تندرست
ہونے پر روزے رکھے.تو ایسی کونسی مجبوری ہے کہ رمضان میں بیمار ہونے کے باوجود روز سے
رکھے جائیں.ٹیکہ لگوانے کی اسی لئے ضرورت پیش آتی ہے کہ ایک شخص بیمار ہے یا ڈاکٹر کے
نزدیک بیماری کی روک تھام کے لئے ٹیکہ لگوانا ضروری ہے.یا حکومت بیماری کے انسداد کے لئے
ٹیکہ لگوا رہی ہے اور بعد میں موقع نہیں ملے گا.ان تمام صورتوں میں روزہ افطار کرنے کی اجازت
ہے.پس روزہ کی حالت میں ٹیکہ لگوانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا.یوں مسئلہ کے طور پر جلدی ٹیکہ مثلاً چیچک کے ٹیکہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا.البتہ انجکشن مثلاً
INTERAMUSCULAR (انٹر اسکولر یا INTERAVENOUS (انٹرا ونیس ، ٹیکہ
سے روزہ ٹوٹ جائے گا.اسی طرح انیما کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے
وہ امور جون سے روزہ نہیں ٹوٹتا
الف : - مسواک خشک و تر.آنکھوں میں دوائی ڈالنے.خوشبو سو لکھنے بلغم حلق میں چلے جانے.
Page 306
گردو غبار حلق میں پڑ جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا.سرمہ کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السّلام کا
ارشاد ہے.دن کو لگانا مکروہ ہے لیے حدیث میں بھی اسی طرح آیا ہے.اسی طرح پچھنے لگواتے تھے کرنے معمولی آپریشن کروانے.خوشیو یا کلورو فارم سونگھنے
سے روزہ نہیں ٹوٹتا.البتہ انہیں پسند نہیں کیا گیا.اس لئے اس قسم کی باتیں مکروہ ہیں.ان کے علاوہ بھی کرنا.ناک میں پانی ڈالنا - خوشبو لگانا.ڈاڑھی یا سر میں تیل لگانا.بار بار
نہانا.آئینہ دیکھنا.مالش کرانا.پیار سے بوسہ لینا.اس میں سے کوئی فعل بھی منع نہیں نہ ان
سے روزہ ٹوٹتا ہے اور نہ ہی مکروہ ہوتا ہے.اسی طرح جنابت کی حالت میں اگر نہانا مشکل
ہو تو نہائے بغیر کھانا کھا کہ روزہ کی نیت کر سکتا ہے.سوال :.روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنے یا زخم پر ٹنکچر آلو ڈین لگانے کا کیا حکم ہے ؟
جواہے :.ٹوتھ پیسٹ غیر پسندیدہ ہے البتہ سادہ برش کرنا.کلی کرنا جائز ہے.اسی طرح بیرونی
اعضاء پر ٹنکچر کا استعمال کیا جاسکتا ہے.والے :.نسوار سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں؟
جوا ہے :.روزہ کی حالت میں نسوارہ ڈالنا مکروہ اور ناپسندیدہ ہے.روزہ کی حالتے ہیں بھول کر کچھ کھا لینا
اگر یاد نہ رہے اور بھول کر انسان کچھ کھا پی لے تو اس کا روزہ علی حالہ باقی رہے گا.اور کسی
قسم کا نقص اس کے روزے میں واقع نہیں ہوگا بلکہ ایسی صورت میں بہتر ہے کہ اگر کوئی بھول کرکھانے
پینے لگ جائے تو پاس کے لوگ اسے یاد نہ دلائیں.کیونکہ اللہ تعالیٰ اسے کھلا پلا رہا ہے پھر انہیں
کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ اس میں روک ثابت ہوں.حدیث میں آتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا :
إِذَا رَكَلَ الصَّائِمُ نَاسِيًا أوْشَرِبَ نَاسِيَّا فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ
اللهُ إِلَيْهِ وَلَا تَضاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَارَةً له
یعنی کوئی روزہ دار بھول کر کھا پی لے تو اسے پریشان نہیں ہونا چاہیے یہ تو رزق تھا جو
اللہ تعالے نے اُسے دیا نہ اُس پر قضاء ہے نہ کفارہ ہے.البتہ اگر کوئی شخص غلطی سے روزہ
توڑ بیٹھے مثلا روزہ یاد تھا لیکن یہ سمجھ کر روزہ کھول لیا کہ سورج ڈوب گیا ہے بعد میں معلوم
له الفضل ۲۸ جولائی مار : ۱۹ - دارقطني كتاب الصوم عن باب الشهادة على روية الهلال نيل الاقطار من :
Page 307
٣٠١
ہوا کہ ابھی تو سورج غروب نہیں ہوا تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کی
قضاء ضروری ہوگی.لیکن اس غلطی کی وجہ سے نہ وہ گنہگار ہے اور نہ اس پر کوئی کفارہ ہے.سوال : کیا کسی حادثہ میں مریض کو خون دینے سے خون دینے والے روزہ دار کا روزہ ٹوٹ جائیگا ؟
جوا ہے.صرف خون دینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا.لیکن چونکہ ایسا کر نے سے کمزوری ہو جاتی ہے اسلئے
روزہ کھول دینا چاہئیے.خون دینا چونکہ انسانی جان کی حفاظت کے لئے بعض اوقات ضروری
ہے اور روزہ تو بعد میں بھی رکھنے کی اجازت ہے اور خُدا تعالیٰ نے یہ رعایت دی ہے.اس
لئے خون دینا چاہیئے.اور جو شخص محض روزہ ے کے صدر پر اس انسانی خدمت سے محروم ہوتا
ہے وہ کوئی نیکی کا کام نہیں کرتا.سوال : - رمضان المبارک کے چھوٹے ہوئے روزہ سے رمضان کے بعد مسلسل یا وقفہ کر کے رکھے
جا سکتے ہیں ؟
جواب : اگر سفر یا بیماری کی وجہ سے رمضان کے روزے رہ گئے ہوں تو بعد میں انہیں پورا کرنا ضروری
ہے.لیکن یہ ضروری نہیں کہ وہ مسلسل رکھے جائیں.وقفہ وقفہ کے بعد بھی رکھے جا سکتے ہیں خواہ
ایک ایک کر کے رکھے.غیر معمولی علاقوں میں رزوں کے اوقات
مبلغ سکنڈے نیویا کو وکیل التبشیر صاحب نے حضرت خلیفتہ اسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ
"
فتوی بھجوایا : -
ایسے ملک کے لئے یہی حکم ہے کہ بارہ گھنٹے کا روزہ رکھیں.سورج کے نکلنے
اور غروب ہونے کا انتظار نہ کریں.کھولنے اور سحری کے اوقات مقرر ک ہیں.اسی طرح
نماز کے.یہ وہ تشریح ہے جو خود رسول اللہ علیہ وسلم نے کی ہے؟ اے
۲ - "رمضان کے مہینے میں دنیا کے تمام مسلمانوں کو خواہ وہ کسی گوشہ میں رہتے ہوں
ایک وقت میں روزے رکھنے کا حکم ہے.وہ صبح کو کو پھٹنے سے پہلے کھانا کھاتے
ہیں اور پھر سارا دن سورج کے ڈوبنے ایک نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں.سورج ڈوبنے
کے بعد صبح تک ان کو کھانے پینے کی اجازت ہوتی ہے.....یہ روز سے تمام ایسے ممالک میں جہاں دن ۲۴ گھنٹے سے کم ہے اور جہاں رات اور
بحوالہ ۲۰ مورخہ ہے.۷۷ فائل دینی مسائل نے
-
Page 308
۳۰۲
گھنٹے کے اندر الگ الگ وقتوں میں ظاہر ہوتے ہیں.اس شکل میں ہے جو
اوپر بیان کی گئی ہے.لیکن جن ملکوں میں رات اور دن چوبیس گھنٹوں سے لیے ہو
جاتے ہیں ان علاقوں میں رہنے والوں کے لئے صرف وقت کا اندازہ کرنیکا حکم ہے لیے
اعتکاف
اعتکاف کے لغوی معنے کسی جگہ میں بند ہو جانے یا ٹھہر سے رہنے کے ہیں.اسلامی اصطلاح
اللَّبْتُ فِي الْمَسْجِدِ مَعَ الصَّوْمِ وَنِيَّةِ الاِمکان ہے یعنی عبادت کی نیت سے روزہ
رکھ کر مسجد میں ٹھہرنے کا نام اعتکاف ہے.روزہ کی طرح اعتکاف کا بھی وجود دیگر مذاہب میں ملتا ہے جیسا کہ قرآن کریم میں ہے :-
وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ
والربع السجود
ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو تاکیدی حکم دیا تھا کہ میرے گھر دخا نہ کعبہ کو طواف کرنے
والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لئے
پاک اور صاف رکھو.اسی طرح حضرت مریم علیہا السلام کے متعلق آتا ہے
وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذا نَتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيَّا
فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا له
یعنی حضرت مریم کچھ عرصہ کے لئے اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کہ عبادت کی خاطر ایک
الگ تھلگ مقام کی طرف چلی گئیں تھیں جہاں انہیں ایک عظیم فرزند کی بشارت ملی تھی.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بعثت سے قبل کے ایام میں دنیوی اشغال سے فارغ ہو کر غار حمد
میں یاد خداوندی میں مشغول رہنا بھی ایک رنگ کا اعتکاف ہی تھا.اعتکاف انسان جب چاہے
اور جس دن چاہے بیٹھ سکتا ہے لیکن رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف بیٹھنا مسنون ہے.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتکاف کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ :.كان يعتكف العشر الاواخر مِن رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللهُ ثُمَّ اعْتَكَفَ
- دیبا چه تغیر القرآن شدم که هدايه باب الاعتكاف : ١٥٣ - سورة البقره : ۱۲۶ : ۱۵ - سورۃ مریم : ۶۱۸۷۱۷
Page 309
سم
ازْواجُهُ مِنْ بَعْدِ لاله
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی وفات تک یہ معمول رہا کہ آپ رمضان کے آخری عشرہ
میں اعتکاف بیٹھا کرتے تھے.آپ کی وفات کے بعد آپ کی ازواج مطہرات بھی اس
سنت کی پیروی کرتی رہیں
انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم لیلتہ القدر کی تلاش کرنے والوں کو رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف
بیٹھنے کی ہدایت فرمایا کرتے تھے.چنانچہ آپؐ کا ارشاد ہے :-
قبل لى أَنَّهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ فَمَن اَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَحْتَكِفَ
فَلْيَعْتَكفَ - فَاعْتَلَفَ النَّاسُ مَعَهُ - له
یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ لیلتہ القدر رمضان کے آخری
عشرہ میں ہے.تم میں سے جو شخص اعتکاف بیٹھنا چاہے وہ اس عشرہ میں بیٹھے
چنانچہ صحابہ آپ کے ساتھ اس آخری عشرہ میں اعتکاف بیٹھتے
حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں :-
عتَكَفْنَا مَعَ النبي صلى الله عليه وسلم الْعَشْرَ الْأَوَسَطَ مِن رَمَضَانَ
قَالَ فَخَرَجْنَا صَبِيعَةَ عِشْرِينَ قَالَ فَخَطَبَنَا رَسُول الله صلى الله عليه
وسلَّم صَبَيْحَةَ عِشْرِينَ فَقَالَ إِلَى رَأَيْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ وَانِي نَسِيتُهَا
فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ فِي الْوِتْرِ فانّى رَأَيْتُ انِّي ! سجد
في ماء وطين....الخ
یعنی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان کے درمیانی عشرہ میں اعتکاف
بیٹھے.۲۰ رمضان کی صبح کو ہم اعتکاف سے باہر نکل آئے اس پر حضور صلی اللہ علیہ
وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب میں لیلۃ القدر دیکھی لیکن مجھے وہ دن یاد
نہیں رہا.البتہ اس قدر یاد ہے کہ میں اس رات پانی اور کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں
دیعنی اس برات بارش ہوگی ، سو تم آخری عشرہ کی تاک راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو.ه: بنجاری من ومسلم کتاب الاعتكاف باب اعتكاف العشر الاواخر الخ ص : سے مسلم باب فضل
ليلة القدر - : بخاری باب الاعتكاف ص ، مسلم فضل ليلة القدر والحث على طلبها الخ من :
Page 310
۳۰۴
اعتکاف کے لئے کوئی میعاد مقرر نہیں.یہ بیٹھنے والے کی مرضی پر منحصر ہے جتنے دن بیٹھنا
چاہیے بیٹھے.اے
تاہم مسنون اعتکاف جو آنحضرت صلی الہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے ثابت ہے یہ ہے کہ ک از کم مشکات
دس دن کا ہو.حدیث میں ہے :-
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَكِفُ فِي كُلِّ رَمَضَانَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ
فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الَّذِى قُبِضَ فِيْهِ اعْتَكَفَ عِشْرِينَ - لَه
یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ماہ رمضان میں دس دن اعتکاف بیٹھا کرتے تھے
البتہ جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال آپ بیس دن کا اعتکاف بیٹھے.اعتکاف بینش رمضان کی نماز فجر سے شروع کرنا چاہیئے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے
میں واضح طور پر موجود ہے کہ آپ دن دن کا اعتکاف فرمایا کہ تھے تھے اور دس دن اسی صورت میں
مکمل ہوتے ہیں جبکہ ۲۰ رمضان کی صبح کو اعتکاف بیٹھا جائے.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے بعد اپنے معتکف میں قیام پذیر ہو جاتے.حضرت عائشہ
کی روایت ہے :-
كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَعْتَكِفُ فِي كُل رَمَضَانَ فَإِذَا
صلى الفدالَا حَلَ مَكَانَهُ الَّذِي اعْتَلِفَ فِيْهِ - ٥٣
ایک روایت میں ہے کہ :.إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَلِفَ صَلَّى الْفَجْرَ ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ له
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف کا ارادہ فرماتے تو نماز فجر ادا کرنے کے بعد اپنے
معتکف میں جو اس غرض کے لئے تیار کیا جاتا چلے جایا کرتے تھے.اعتکاف کے لئے موزوں اور مناسب جگہ جامع مسجد ہے جیسا کہ قرآن میں ذکر ہے :.وَانْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِد :.کیونکہ مساجد ہی اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کی عبادت کے لئے مخصوص ہیں اور احادیث میں مسجد میں ہی
: ہدایہ منا فقه مذا ہب اربعہ تک اردو : : - بخاری باب الاعتكاف في العشر ص :
: - بخاری باب الاعتكاف في شوال م : که اسلم باب متى يدخل من اراد الاحتكات : : - بقره ۶۱۸۸۱
Page 311
اعتکاف بیٹھنے کی تاکید ہے.چنانچہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں :-
لا اعتكانَ إِلَّا فِي مَسْجِدِ جَامِعٍ :
گو مجبوری کی بناء پر مسجد کے باہر بھی اعتکاف ہوسکتا ہے.حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ
فرماتے ہیں :.او مسجد کے باہر اعتکاف ہو سکتا ہے.مگر مسجد والا ثواب نہیں مل سکتا ہی ہے
عورت بھی مسجد میں اعتکاف بیٹھ سکتی ہے لیکن گھر میں نماز کے لئے ایک الگ جگہ مخصوص
کر کے وہاں اعتکاف بیٹھنا اس کے لئے زیادہ بہتر ہے.ہدایہ میں ہے :-
" أَمَّا الْمَرْأةُ تَعْتَكِفُ فِي مَسْجِدِ بَيْتِهَا ".معتکف کے لئے حوائج ضروریہ کے علاوہ کسی اور وجہ سے مسجد سے باہر نکلنا جائز نہیں
یہاں تک کہ عام نہانے اور بال کٹوانے کے لئے بھی مسجد سے باہر نہیں آنا چاہئیے.البتہ ضروری اور
مثلا و ضوء غسل جنابت کے لئے مسجد سے نکلنا جائزہ ہی نہیں بلکہ ضروری ہے.اعتکاف کے دوران اگر عورت کو ماہواری ہو جائے تو وہ اعتکاف ترک کر دے.اس
-
حالت میں اس کا مسجد میں رہنا درست نہیں ہوگا
مختلف ذکر الہی اور عبادت میں زیادہ سے زیادہ وقت صرف کر سے فضول باتوں میں
وقت ضائع کرنا درست نہیں اور نہ بالکل خاموش رہنا درست ہے کیونکہ اسلام میں چپ کا
روزہ نہیں ہے." ولا يتكلم إلَّا بِخَيْرٍ وَيُكْرَهُ لَهُ الصَّمَدُ لِاَنَّ صَوْمَ الصَّمْتِ
لَيْسَ بِقُرْبَةٍ له
اعتکاف کچھ اہمیتے
رسول کریم صلی الہ علیہ وسلم نے مختلف کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا.اخرج البيهقى عن عطاء الخراساني قال ان مثل المعتكف مثل المحرم
: ابو داؤد کتاب الاعتكاف باب المعتكف يعود المريض م۳ : ۱۹ - الفضل و ر مارچ :
: - صدا یہ باب الاعتکاف من : -0-1- هدا یه باب الاعتكاف ا ب شود.
Page 312
القى نفسه بين يدي الرحمن فقال والله لا ابرم حتى ترحمني بيه
یعنی مختلف کلی طور پر اپنے آپ کو خدا کے حضور میں ڈال دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے
خُدا تجھے تیری ہی قسم میں یہاں سے نہیں ہٹوں گا یہاں تک کہ تو مجھ پر رحم فرمائے.نیز فرمایا :
مَنِ اعْتَكَفَ يَوْمَا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ جَعَلَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ
ثَلاثَ خَنَادِقَ ابْعَدُ مِمَّا بَيْنَ الْحَا فَتَيْنِ هِ
یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ایک دن اعتکاف بیٹھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے
اور جہنم کے درمیان تین ایسی خند قیس بنادے گا جن کے درمیان مشرق و مغرب کے
مابین فاصلہ سے بھی زیادہ فاصلہ ہوگا.عَنِ ابْنِ عَبَّاس اَن رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْمُعْتَكِفِ
هُو يَعْتَكِفُ الذُّنُوبِ
يختلف عَنِ اللَّهِ نُوبِ وَيَجْرِى لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ لَعَامِلِ الحَسَنَا
كلها
الحَسَنَات
یعنی.رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف
کرنے والے کے متعلق فرمایا کہ متکف
اعتکاف کی وجہ سے جملہ گنا ہوں سے محفوظ رہتا ہے.اُسے ان نیکیوں کا بدلہ جو اس
نے اعتکاف سے پہلے بجالائی تھیں اسی طرح اخیر ملتا رہتا ہے جیسا کہ وہ اب بھی
انہیں بنجارا رہا ہے.فتاوی
سوال: کیا یہ جائز ہے کہ جامع مسجد کے سوا کسی قریبی مسجد میں اعتکاف بیٹھا جائے ؟
جواب : - صحت اعتکاف کے لئے ضروری شرط ایسی مسجد ہے جس میں باجماعت نمازہ ہوتی ہے.ابو داؤد کی حدیث ہے کہ :-
لا اعْتِكَانَ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ " له
در منثور جلد اول زیر اتيت وانتم ماكفون في المساجد - در مشورت بلا دل بحوالہ طبرانی اوسط و بیعتی
: ابن ماجہ کتاب الاعتکاف باب ثواب الاعتكان ما : ه: - ابو داود المحتلف يعود المريض ٣٣ :
-
Page 313
یعنی اعتکاف ایسی مسجد میں ہو سکتا ہے جس میں باجماعت نماز ہوتی ہو.قریباً سارے
ائمہ اس رائے پر متفق ہیں.لے
سوال : کیا ایسی جگہ جہاں مسجد نہ ہو گھر میں اعتکاف بیٹھا جا سکتا ہے ؟
جوا ہے :.جب باقاعدہ عام مسجد میسر نہ آئے مثلاً کہیں اکیلا احمدی رہتا ہے یا مقامی جماعت کے
افراد کسی دوست کے گھر میں نماز ادا کرتے ہیں تو ایسی صورت میں اپنے گھر میں ایسی جگہ جو نماز
کے لیئے عام طور پر مخصوص کر لی گئی ہو اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں.مجبوری کے حالات
کو اللہ تعالیٰ
جانتا ہے اور وہ بند ے کی نیت کے مطابق اعمال کا ثواب دیتا ہے.سوال : کیا عورت گھر میں خلوت والی جگہ میں اعتکاف بیٹھ سکتی ہے ؟
جواب : اگر کسی جگہ مسجد نہیں یا مسجد میں عورت کے لئے رہائش کا معقول انتظام نہیں تو عورت
گھر س ایک خاص جگہ مقررہ کر کے وہاں اعتکاف بیٹھ سکتی ہے.ہر احمدی گھرانے میں جہاں تک ممکن ہو سکے ایک ایسی جگہ ہونی چاہیے جو مسجد البیت رگھر
کی مسجد کے طور پر ہو.گھر کی عورتیں وہاں نما نہ پڑھیں اور مرد سنتیں اور نوافل وغیرہ ادا کریں
اور مشکلات کے موقع پر وہاں خلوت گزیں ہو کر دعائیں کی جائیں.یہ طرفہ عمل بڑی برکات کا
موجب ہے اور صحابہ کا اکثر اس کے مطابق عمل تھا.سوال : کیا بوڑھے آدمی کے لئے جس کے لئے روزہ رکھنا مشکل ہے بغیر روزے کے مسجد میں
اعتکاف بیٹھنا جائز ہے ؟
جوا ہے :.عام حالات میں اعتکاف کے لئے روزہ ضروری شرط ہے.حضرت عائشہ نہ سے روایت ہے
له
کہ روہہ کے بغیر اعتکاف درست نہیں.روایت کے الفاظ یہ ہیں: "لا اعتكاف الا بصوم
آیت کو نہ ثُمَّ اتموا القِيَامَ إلى الميل ولا تباشروهن وانتم عاكفون
في المساجد کا انداز بیان بھی اسی مسلک
کی تائید کرتا ہے.علاوہ ازیں یہ تصریح کہیں نہیں
ملتی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے صحابہ کبھی روزہ کے بغیر اعتکاف بیٹھے ہوں.صحابہ
میں سے حضرت ابن عباس - حضرت ابن عمر اور ائمہ میں سے امام مالک.امام ابو حنیفہ.امام
روز اعلی کا یہی مسلک ہے اور سلسلہ احمدیہ کے بزرگان کی بھی یہی رائے ہے اس کے برعکس
حسن بصری.امام شافعی اور امام احمد اعتکاف کے لئے روزہ کو شرط نہیں مانتے.یہ بزرگ
اپنی رائے کی تائید میں یہ روایت پیش کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عمریض نے پوچھا کہ میں نے
- نیل الاوطار له -: ابوداؤد کتاب الاعتكاف باب المعتكف يعود المريض
:- البقرة : ١٨٨:
۳۳۵
Page 314
ایک رات کے اعتکاف کی نذر مانی تھی کیا میں نذر پوری کروں.آپ نے فرمایا.ہاں.چنانچہ حضر
عمرو نے ایک رات اعتکاف میں گزاری یہ
اس روایت سے معلوم ہوا کہ اعتکاف کے لئے روزہ ضروری نہیں کیونکہ رات کو روزہ
نہیں رکھتے.اسی بناء پر ان ائمہ کے نزدیک دو گھڑی بھی اعتکاف جائز ہے.لہ
سوال ہے :.اعتکاف کے دوران کیا انسان رات کو مسجد میں چارپائی بچھا کر سو سکتا ہے ؟
جواب : اعتکاف کے دنوں میں ضرورت پڑنے پر مسجد کے کسی کونے میں یا کسی اور مناسب جگہ میں
چارپائی بچھا کر سونا جائز ہے.اس میں کوئی حرج نہیں.بشر طیکہ ایسا کرنے سے مسجد میں نمازہ
پڑھنے والوں کو کوئی وقت پیش نہ آئے.حدیث میں آتا ہے :-
اِنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ إِذَا اعْتَكَفَ طُرِح لَهُ
فراتُهُ وَيُوْضَعُ لَهُ سَرِيدُهُ وَرَاءَ اسْتُوَانَةِ التَّوْبَةِ " ٣
یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف شروع فرماتے تو آپ کے لئے بستر بچھایا جاتا
اور ایک ایسے ستون کی اوٹ میں آپ کی چارپائی بچھائی جاتی جس کا نام تو یہ کاستون
تھا.ایک مشہور واقعہ کی وجہ سے اس ستون کا نام استوانہ پڑ گیا تھا.سوال : حدیث میں آتا ہے کہ مختلف حوائج ضروریہ کے لئے مسجد سے باہر جا سکتا ہے.جوائیے
ضروریہ سے کیا مراد ہے؟
جوا ہے :.حدیث کے الفاظ یہ ہیں :-
كَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ إِذَا كَانَ مُعْتَلِفًا :
یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کی حالت میں سوائے انسانی حاجت کے
گھر میں نہیں آتے تھے
انسانی حاجت سے مراد کیا ہے.اس کا ایک مفہوم بیت الخلاء جاتا ہے اس مفہوم
پر تمام علماء کا اتفاق ہے کہ یہ ایسی ضرورت ہے جس کے لئے مسجد سے باہر آنا ضروری ہے.ه : بخاری کتاب الاعتكان باب اذا نذر في الجاهلية م ، ابو داو ده سه : - نیل الاوطار ص :
-
: این ماجر كتاب الاعتكاف باب في المعتكف يلزم مكانا من المسجد فا ، نيل الأوطار ص :
۱۹ حاشیه این اجر حاشیه ۲ : شه مسلم کتاب الطهارة باب جواز نغسل الحائض رأس زوجها الخرما :
Page 315
ر اسی طرح اگر محل کی مسجد میں اعتکاف بیٹھا ہے تو جمعہ پڑھنے کے لئے جامع مسجد جانے کی بھی
اجازت ہے اور اسے بھی حاجت انسانی سمجھا گیا ہے.ان کے علاوہ باقی ضروریات مثلاً
درس القرآن یا اجتماعی دعا میں شامل ہونے.بال کٹوانے.کھانا کھا نے نماز جنازہ پڑھنے.کسی عزیز کی بیمار پرسی کرنے یا کسی کی مشابہت کے لئے باہر آنے کی اجازت میں اختلاف
ہے.اکثر ان اغراض کے لئے مسجد سے باہر آنے کو جائز نہیں سمجھتے اور اعتکاف کی روح
بھی اس امر کی مقتضی ہے کہ ان ثانوی اغراض کے لئے مختلف مسجد سے باہر نہ آئے بلکہ
کلی انقطاع کی کیفیت اپنے اوپر وارد کرنے کی کوشش کر سے اور اس قسم کی ترغیبات اور خواہشات
کی قربانی دینے کا اپنے آپ کو عادی بنائے.سوال :.اعتکاف سے متعلق مشہور ہے کہ شاذ و نادر حالات کے سوا مختلف مسجد سے باہر نہ
جائے.شاذ و نادر حالات کی مثال قضائے حاجت کے لئے باہر جانا ہے یا عدالت میں
کسی ضروری شہادت کی غرض سے جس میں التواء کی صورت نقصان دہ ہو.یا بعض نے جنازہ
کے لئے بھی اجازت دی ہے یہ پابندی نہ ہو تو اعتکاف کی غرض و غایت مفقود ہو جاتی ہے
لیکن بعض بزرگ ان پابندیوں کی پرواہ نہیں کرتے.اور بعض تو دفتر میں جا کہ اپنا دفتری کام
بھی کر لیتے ہیں صحیح صورت حال کی وضاحت کی جائے ؟
جوا ہے :.گلی انقطاع اعتکاف کا اعلیٰ درجہ ہے.حضرت عائشہ فرما یا کرتی تھیں کہ سنت یعنی آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق کی متابعت یہ ہے کہ مختلف مسجد سے باہر نہ نکلے نہ بیمار کی عیادت
کے لئے اور نہ ہی جنازہ میں شامل ہونے کے لئے.ہاں حوائج ضروریہ کے لئے باہر جا سکتا ہے اور
حوائج ضروریہ سے مراد بیت الخلاء جاتا ہے.کہ
تاہم بعض فقہاء نے کہا ہے کہ حوائج ضروریہ میں کچھ وسعت ہے بعض اور ضرورتوں کے
لئے بھی مختلف مسجد سے باہر جا سکتا ہے.خاص طور پر ضروری شہادت کے لئے جانے کی
اہمیت مسلم ہے.کیونکہ
1 : ممانعت کے بارہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی صریح ارشاد موجود نہیں.لہ :.سوائے اس کے کہ مجبوری ہو مثلاً گھر سے کھاناں نے والا کوئی نہ ہو :
- -:- ابوداؤد کتاب الصیام باب المعتكف يعود المريض ۳۳۵ :
Page 316
ب : اعتکاف کا لغوی مفہوم صرف یہ ظاہر کرتا ہے کہ انسان عبادت کی نیت سے مسجد
میں کچھ عرصہ کے لئے بیٹھے رہے.ج : بعض روایات سے بھی اشارہ اس کی تائید ہوتی ہے کہ انسان کسی اور ضرورت کے پیش
نظر بھی مسجد سے باہر جا سکتا ہے.مثلاً ایک بار حضرت صفیہ رات کو آپ سے ملنے
گئیں اور دیر تک باتیں کرتی رہیں اور جب واپس ہوئیں تو آپ انہیں گھر تک
پہنچانے آئے.حالانکہ گھر مسجد سے کافی دور تھا.لہ
د : - جس امر کے جائز ہونے کا ائمہ میں سے کوئی امام قائل ہو اس کے متعلق اصول یہ
ہے کہ ضرورت اور مجبوری کے حالات میں اسے اختیار کرنے کا عمل روحانی ترقی اور
ثواب کے حصول کے منافی نہیں.سابقہ ائمہ میں سے جو لوگ اس قسم کے استثنا ءاور
ضرورت کے لئے مسجد سے باہر آنے کے جوانہ کے قائل ہیں.ان کے نام یہ ہیں:-
حضرت علی نے سعید بن جبیر قتادہ ابراہیم نخعی حسن بصری اور امام احمد - شد
پس جو لوگ اپنے بعض ضروری کاموں کی وجہ سے اعلی درجہ کا عین سنت کے مطابق
اعتکاف نہیں بیٹھ سکتے وہ ان دلائل کے پیش نظر دوسرے درجہ کے اس اعتکاف میں
شامل ہو سکتے ہیں تاکہ ثواب سے وہ بکلی محروم نہ رہیں.ایسی صورت میں وہ اعتکاف کی
نیت کرتے وقت اپنے بعض ضروری کاموں کے لئے مسجد سے باہر جانے کے استثناء کی نیت
کہ سکتے ہیں.حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور حضرت خلیفتہ اسیح الثانی رضی اللہ تعالٰی عنہ کے
ان ارشادات کا تعلق بھی غالباً اسی دوسرے درجہ کے اعتکاف سے ہے جن میں بعض دوسری
ضروریات کے لئے مسجد سے باہر جانے کی اجازت کا ذکر ہے.سوال: کیا اعتکاف کی صورت میں کالج میں درس و تدریس کے لئے جانا جائز ہے ؟
ہوا ہے :.بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کو ان کے کرنے یا نہ کرنے کا اختیار ہوتا ہے لیکن اگر
ان کو کیا جائے تو پھر ضروری شرائط کے ساتھ ان کی بجا آوری مشروط ہے.اعتکاف کا بھی یہی
حال ہے.آپ چاہیں تو اعتکاف بیٹھیں اور چاہیں تو اپنے حالات کے پیش نظر یہ ک کریں.یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ مسنون اعتکاف کی نیت سے اعتکاف بھی بیٹھیں اور پھر اپنی مرضی کو
بھی اس میں دخل اندا نہ ہونے دیں.اعتکاف کے لغوی معنے یہ ہیں کہ انسان ثواب اور عبادت سمجھ کر کچھ دیر کے.له : - ابو داؤد باب المعتكف يدخل البيت لحاجه ۳۳۵ ، بخاری : ۱۳ - اوجز المسالک ص :
Page 317
میں مقیم رہے اس لئے عبادت کی نیت سے چند منٹ کا قیام بھی اعتکاف ہوگا لیکن مسنون
اعتکاف جو رمضان کے آخری عشرہ میں اختیار کیا جاتا ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ ضروری
یا طبعی حوائج کے علاوہ باقی کسی وجہ سے بھی مسجد سے باہر نہ نکلے اور ضروری حوائج میں کالج آکر
سبق سننا شامل نہیں.حدیث میں آتا ہے.السُّنَّةُ عَلَى الْمُعْتَلِفِ أَن لَّا يَعُودَ مَرِيضًا وَلَا يَشْهَدَ جَنَازَةً وَلَا
يَمَسَّ امْرَأَةٌ وَلَا يُبَاشِرَهَا وَ
ا وَلا يَخْرُجَ لِحَاجَةٍ إِلَّا لابد
مِنْهُ - وَلَا اعْتَكَانَ إِلَّا بِصَوْمِ وَلَا اِعْتِكَافَ إِلَّا فِى مَسْجِدٍ جَامِعٍ -
اسی طرح حضرت عائشہ فرماتی ہیں:." إِن كُنتُ لاَدْخُلُ البَيْتَ لِلْحَاجَةِ وَالْمَرِيضُ فِيهِ تَمَا
اسْاَلُ عَنْهُ إِلَّا وَأَنَا مَارَةٌ له
یعنی معتکف کے لئے مستون یہ ہے کہ وہ مریض کی عیادت کے لئے نہ جائے.جنازہ میں
شامل نہ ہو.اپنی بیوی کے پاس نہ جائے.مسجد سے انسانی حوائج پیشاب.قضائے
کے سوا باہر نہ جائے.اعتکات کیلئے روزہ ضروری ہے.اسی طرح اعتکاف
الیسی
میں بیٹھنا چاہئیے جہاں نما نہ باجماعت ہوتی ہو.حضرت عائشہ نہ فرماتی ہیں.سب بھی میں قضائے حاجت کے لئے گھر آتی اور گھر میں کوئی بیمار ہوتا تو چلتے چلتے اس کی
طبیعت پوچھ لیتی ، دھرنے کو رد نہیں سمجھتی
حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے عیادت مریض کے جواز کے بارہ میں جو سکھا ہے اس کا
بھی غالبا یہی مطلب ہے کہ ایسے رنگ میں عیادت جائز ہے.سوال : اعتکاف کا مسنون طریقہ کیا ہے ؟
خواہے :.مسنون اعتکاف وہی ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق کے مطابق ہو در جوحد شوں
سے ثابت ہے اور وہ یہ ہے کہ رمضان کا آخری عشرہ آپ مسجد میں روزہ سے گزار نے اور
حوائج ضروریہ کے علاوہ باقی کسی ضرورت سے مسجد سے باہر نہ آتے.له : ابوداود كتاب الاعتكاف باب المعتكف يعود المريض م٣٣ :
ه: ابن ماجد كتاب الصوم باب فى المعتكف يعود المريض - الخرص.
Page 318
۳۱۲
یہ مکمل اور سنت کے مطابق اعتکاف ہے.لیکن اگر کوئی اس کے لئے اپنے حالات کے
اعتبار سے گنجائش نہ پائے تو اس میں کمیاں کی جاسکتی ہیں.مثلا اگر کوئی پور اعشرہ نہ بیٹھ
کے تو وہ حسب گنجائیش و دن - ۸ دن دن اور اسے بھی کم دن اعتکاف بیٹھ سے
تو اللہ تعالیٰ کے حضور سے ایسا کرنے والا ثواب کا مستحق ہوگا.اسی طرح اگر کوئی روزہ نہیں
رکھ سکتا تو اپنا وقت مسجد میں اللہ تعالیٰ کے ذکر میں صرف کر کے اپنی کوشش کے مطابق
اعتکاف کا تو اب حاصل کر سکتا ہے.یہی حال ان لوگوں کا ہے جو پور اسالم دن اعتکاف
کے لئے نہیں بیٹھ سکتے تو انہیں جتنی گھڑیاں مسجد میں عبادت میں میسر آسکتی ہیں یہ
ان کی سعادت کا موجب ہوں گی.انشاء اللہ تعالیٰ.ائمہ سلف نے ان حالات میں ایسی رعایتوں کی تصریح کی ہے اور اعتکاف کے جذبہ
کو قوی رکھنے کے لئے حوصلہ افزائی کے پہلو کو ترجیح دی ہے.سوال : کیا حوائج ضروریہ کے لئے اگر قریب انتظام نہ ہو تو مختلف دُور بھی جاسکتا ہے ؟
جواب: - حوائج ضروریہ کے لئے اگر قریب انتظام نہیں تو دور فاصلہ پر جا سکتے ہیں.لیکن فراغت
کے بعد فورد ا مسجد میں واپس آجائیں.سوال : کیا مختلف جماعتی میٹنگ یا جماعتی کاموں کے لئے مسجد سے باہر جا سکتا ہے ؟
جواہے :.جہاں تک ممکن ہو جو ائج ضروریہ کے علاوہ کسی اور کام کے لئے مسجد سے باہر نہ جائے
ورنه مسنون اعتکاف ادا نہیں ہو گا.ہاں وقتی اعتکاف یعنی مسجد کی عبادت کا ثواب بیشتر
آسکتا ہے.سوال سے : کیا کھانا کھانے کے لئے مختلف گھر جا سکتا ہے یا بازار سے کھانا لا سکتا ہے ؟
جوا ہے :.اگر کھانا لانے کا کوئی انتظام بہولت نہ ہو سکے تو گھر سے کھانا لایا جا سکتا ہے.اسی طرح
بازار سے بھی.سوال : اگر مسجد میں غسل کا انتظام نہ ہو تو کیا غسل کے لئے گھر جا سکتے ہیں ؟
جوا ہے :.اگر پہلے سے بطور نیست غسل کو حوائج ضروریہ میں شامل کر لیا جائے تو اس کے لئے گھر
جا سکتا ہے.وضو اور ضروری غسل تو پہلے ہی حوائج ضروریہ میں شامل ہے.اس مقصد
کے لئے مسجد سے باہر آسکتا ہے.سوال.کیا اعتکاف کی حالت میں مسجد میں بیٹھ کہ حجامت بنوانا اور بال کٹوانا درست ہے.کیا
Page 319
۳۱۳
اس
سے آداب مسجد میں کوئی حرج تول ازم نہیں آتا ؟
جواب: - اعتکاف کی حالت میں بال کٹوانے اور حجامت بنوانے میں کوئی حرج نہیں.البتہ مسجد
کے اندہ اسے نا پسند کیا گیا ہے کیونکہ یہ امر مسجد کے احترام اور اس کے آداب کے خلاف
ہے.اکثر علماء امت کا یہی مسلک ہے.چنانچہ موطا امام مالک کی شرح اوجز المسالک میں
لکھنا ہے...وَيُكْرَهُ خَلْقُ الرَّأْسِ فِيْهِ مُطْلَقًا رَى مُعْتَلِفًا كَانَ أَوْ غَيْرَ..وَذَلِكَ لِحُرَمَةِ الْمَسْجِد لم
یعنی مسجد میں بال کٹوانا نا پسندیدہ ہے.یہ ممانعت مسجد کے احترام کے پیش نظر
مختلف..ہے.اعتکاف کی وجہ سے نہیں.کیونکہ حجامت بنوا نا منائی اعتکاف نہیں.روایات میں آتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت اعتکاف میں جب بالوں میں کنگھی
کرنا ہوتی تو آپ اپنا سر مسجد سے باہر کر دیتے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو اپنے حجرہ میں
ہو تیں آپ کو کنگھی کر دیتیں.حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں ایک سوال پیش ہوا کہ معتکف اپنے دنیوی
کاروبار کے متعلق بات کر سکتا ہے یا نہیں تو آپ نے فرمایا :-
ا سخت ضرورت کے سبب کہ سکتا ہے اور بیمار کی عیادت کے لئے اور حوائج
ضروریہ کے واسطے باہر جا سکتا ہے " سے
صاحب صدا یہ لکھتے ہیں :
لا بَأسَ بِأَن تَبِيعَ وَيَبْتَاعَ فِي الْمَسْجِدِ مِنْ غَيْرِ انْ تَحْضِرَ
السلعة ، له
حضرت خلیفہ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں :-
اعتکاف بیسویں کی صبح کو بیٹھتے ہیں کبھی دس دن ہو جاتے ہیں اور کبھی گیارہ.....ایک دفعہ رسول کریم صلی الہ علیہ وسلم دوسروں کو قبولیت دعا کا وقت بتانے
کے لئے باہر نکلے تھے مگر اس وقت دو آدمی آپس میں لڑتے ہوئے آپ نے
ن: اوجز المسالك قالا : :- بدر ۲۱ فروری عنه : ه: - هداية من جلد اول :
Page 320
۳۱۴
دیکھے تو فرمایا کہ تم کو دیکھ کر مجھے وہ وقت بھول گیا ہے مگر اتنا فرما دیا کہ ماہ
رمضان کی آخری دس راتوں میں یہ وقت ہے.صوفیاء نے لکھا ہے کہ ان
راتوں کے علاوہ بھی یہ وقت آتا ہے مگر یہ مضان کی آخری راتوں میں قبولیت دعا
کا خاص وقت ہوتا ہے.حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے تجربہ کی بناء پر فرمایا کہ ستائیسویں
کی رات کو یہ وقت ہوتا ہے.سالہ
ه : - الفضل ٣ أومبر اء
Page 321
۳۱۵
حج
اُس کی اہمیت اُسکا فلسفہ اور اس کے احکام
ایت
خانہ کعبہ جسے بیت اللہ بھی کہتے ہیں اس کی زیارت کی نیت سے مکر جانا ج کہلاتا ہے.اس
زیارت کی کئی شرائط ہیں جن کا تفصیلی ذکر بعد میں آئے گا.اس وقت قرآن کریم کی ان آیات کو
پیش کرنا مد نظر ہے جن میں حج کی تاریخی حیثیت اور اس کے احکام کا علی الا جمالی ذکرہ آیا ہے.اللہ تعالی قرآن کریم میں بیت اللہ کی عظمت اور اس کی تاریخی اہمیت کے سلسلہ میں فرماتا ہے :-
ا - إن أوّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَةٌ مُبرَكا وَهُدًى لِتَعْلَمينَ.فِيهِ أَنتُ بَيِّنْتُ مَقَامُ ابْراهِيمَةً وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ أَمِناط
یعنی سب سے پہلا گھر جو تمام لوگوں کے فائدہ کیلئے بنایا گیا تھا وہ ہے جو مکہ میں ہے.وہ تمام
جہانوں کے لئے برکت والا مقام اور موجب صدایت ہے.اس میں کئی روشن نشانات
ہیں وہ ابراہیم کی قیام گاہ ہے اور جو اس میں داخل ہو وہ امن میں آجاتا ہے.حضرت ابراہیم کے ہاتھوں
بیت اللہ کی تعمیر ثانی کے سلسلہ میں فرمایا.۲ - وَإِذْ يَرْفَعُ الْرَجِمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّاء
إنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيْمُه رَبَّنَا وَاجْعَلُنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَ مِنْ
ذُريَّتِنَا أُمَّةٌ مُسْلِمَةٌ لَّكَ وَ آرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ
أنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُه رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُوا
عَلَيْهِمْ : ALONE الكتب وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ
انْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.اور اس وقت کو بھی یاد کر جب ابراہیم اس گھر کی بنیا دیں اُٹھا رہا تھا اور اس کے ساتھ
اسمعیل بھی اور وہ دونوں کہتے جاتے تھے کہ اسے ہمارے رب ہماری طرف سے اس خدمت کو
ه : سوره آل عمران ۱۹۸۰۹۰۱ ۵۲:- سوره البقره ۱ ۱۱۸ تا ۱۳۰ ۹
Page 322
114
قبول فرما.تو وہی ہے جو بہت سُننے والا اور بہت جاننے والا ہے.اسے ہمار سے رب اور ہم یہ بھی التجا کرتے ہیں کہ ہم دونوں
کو اپنا فرمانبردار بندہ بنا.اور ہماری اولاد میں سے بھی اپنی ایک فرمانبردار جماعت بنا.اور ہمیں ہمارے مناسب
حال عبادت کے طریق بتا.اور ہماری طرف اپنے فضل کے ساتھ توجہ فرما.یقینا تو اپنے
بندوں کی طرف بہت توجہ کرنے والا اور بار بارہ رحم کرنے والا ہے.اور اسے ہمارے
سے
رب ہماری یہ بھی التجا ہے کہ تو انہیں میں سے ایک ایسا رسول مبعوث فرما جو انہیں تیری
آیات پڑھ کر سُنائے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھائے اور انہیں پاک کر ہے.یقینا تو ہی غالب اور حکمتوں والا ہے ؟؟
وَادُ بَوَّانَا لا بَهِيمَ مَكَانَ البَيْتِ أَن لَّا تُشْرِكَ بِي شَيْئًا
وَطَهِرْ بَيْتِيَ لِلطَّا فينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِه
اور جب ہم نے ابراہیم کو بیت اللہ کی جگہ پر رہائش کا موقعہ دیا اور کہا کہ کسی چیز کو
ہمارا شریک نہ بناؤ اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لئے اور کھڑے ہو کر عبادت
کرنے والوں کے لئے اور رکوع کرنے والوں کے لئے اور سجدہ کرنے والوں کے لئے
پاک کند و به
٤ - وَإِذْ جَعَلْنَا البَيْتَ مَثَابَةٌ لِلنَّاسِ وَاَمْنًا ، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ
اِبْرَاحِمَ مُصَلَّى ، وَعَهِدْنَا إِلَى إبْرَاحِمَ وَاسْمَعِيلَ أَن طَهِرًا
بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَلِمِينَ وَالرُّكَّع السجوده
اور اس وقت کو بھی یاد کر و جب ہم نے اس گھر یعنی کعبہ کو لوگوں کے لئے بارہ بار جمع
ہونے کی جگہ اور امن کا مقام بنایا تھا.اور حکم دیا تھا کہ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی
جگہ کو نمانہ کا مقام بناؤ.اور ہم نے ابراہیم اور اسمعیل کو تاکیدی حکم دیا تھا کہ میرے گھر
کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے
والوں کے لئے پاک اور صاف رکھو.ه - وَ اِذْ قَالَ إِبْرهِم رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا أَمَنَا وَالذُقُ أَهْلَهُ.مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ
تفرَ فَأَ مَتِّعَهُ قَلِيلًا ثُمَّ اَضْطَرُةٌ إلى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ المَصِيرُة
1 - سورة الحج : ۲۷ : سورة البقرہ : ۱۲۶ له :- سورة البقره : ۱۲۷ :
Page 323
اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب ابراہیم نے کہا تھا کہ اسے میرے رب اس جگہ کو
ایک پر امن شہر بنا دے اور اس کے باشندوں میں سے جو بھی اللہ پر اور آنیوالے
دن پر ایمان لائیں انہیں ہر قسم کے پھل عطا فرما.اس پر اللہ نے فرمایا اور جو شخص
کفر کر سے اُسے بھی میں تھوڑی مدت تک فائدہ پہنچاؤں گا.پھر اُسے مجبور کر کے
دوزخ کے عذاب کی طرف سے جاؤں گا.اور یہ بہت برا انجام ہے.- وَاذْنَ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَ عَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَّاتِينَ
منْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيْقَ لِيَشْهَدُ وَا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ
اللهِ فِي اَيَّامٍ مَّعْلُومَت عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ
فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا البَائِسَ الْفَقِيْرَهُ ثُمَّ لَيَقْضُوا نَفَتَهُم
وليو فوانُذُورَهُمْ وَلْيَطَوَّنُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِه له
اور تمام لوگوں میں اعلان کر دے کہ وہ حج کی نیت سے تیرے پاس آیا کہ میں پیدل بھی
اور ہر ایسی سواری پر بھی ہو لیے سفر کی وجہ سے دبلی ہوگئی ہو.ایسی سواریاں دُور دُور
سے گہرے راستوں پر سے ہوتی ہوئی آئیں گی.تاکہ وہ یعنی آنے والے ان منافع کو ا
دیکھیں جو ان کے لئے مقرر کئے گئے ہیں اور کچھ مقرنہ دنوں میں اللہ کو ان نعمتوں
کی وجہ سے یاد کریں.بہو ہم نے ان کو دی ہیں یعنی بڑے جانوروں کی قسم کر جیسے
اُونٹ گائے وغیرہ پس چاہیئے کہ وہ ان کے گوشت کھائیں اور تکلیف میں
پڑے ہوئے نادار کو کھلائیں.پھر اپنی میل دور کریں اور اپنی نذریں پوری کریں.اور
پیرا نے گھر یعنی خانہ کعبہ کا طواف کریں.۷ - وَلِلّهِ عَلى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلَاء وَمَنْ
كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ عَنِي عَنِ الْعَلَمِينَ ٢٠٥
اور اللہ نے لوگوں پر فرض کیا ہے کہ وہ اس گھر کا حج کریں یعنی جو بھی اس تک جانے
کی توفیق پائے اور جو انکار کر سے تو وہ یاد رکھے کہ اللہ تمام جہانوں سے بے پروا ہے.فلسفه حج
ج ایک عاشقانہ عبادت ہے جب ایک شخص کسی سے محبت کرتا ہے اور اس کا عاشق ہے
ے :.سورۃ الحج : ۲۸ تا ۳۰ له :- سورة ال عمران : ۹۸ :
Page 324
۳۱۸
تو وہ اپنے محبوب اور معشوق کو راضی اور خوش کرنے کے لئے مختلف جتن کرتا ہے.اپنا حال
بے حال کر لیتا ہے.دیوانوں کی طرح پھرتا ہے محبوب کے گھر کے اردگرد چکر لگاتا ہے.اس
سے تعلق رکھنے والی چیزوں سے پیار کرتا ہے انہیں چومنے لگتا ہے اور یہ سارے والہانہ
اندانہ اس لئے اختیار کرتا ہے تاکہ اس کا محبوب کسی طرح اُس پر خوش ہو جائے.پیار کی نظر
سے اُسے دیکھے ملاپ اور وصال کی کوئی صورت نیکل آئے.ایک مومن کا چونکہ حقیقی محبوب
اس کا اللہ ہے اس لئے اس کے جذبہ محبت کی تسکین کے لئے پیار اور اس کے اظہار کے
لئے کچھ نمونے حج کی عبادت میں رکھے گئے ہیں.وہ آن سیلی دو چادریں پہنتا ہے.سرسے ننگا
ہوتا ہے.پاؤں میں چپل ہوتے ہیں.بال بکھرے بکھر سے سے رہتے ہیں کیونکہ کنگھی کہ نیکی اجازت
نہیں - لبيك لبيك " میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں.کہتا ہوا اللہ کے گھر کا رخ کرتا ہے
حجر اسود کو چومتا ہے.بیت اللہ کے ارد گرد گھومتا اور چکر لگاتا ہے.یہ سب کچھ اظہار محبت
کے والہانہ انداز ہیں.شید نا حضرت مسیح موعود علیہ السلام حج کی اس حکمت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے
ہیں:." محبت کے عالم میں انسانی روح ہر وقت اپنے محبوب کے گرد گھومتی ہے اور
اس کے آستانہ کو بوسہ دیتی ہے.ایسا ہی خانہ کعبہ جسمانی طور پر محبان صادق
کے لئے ایک نمونہ دیا گیا ہے اور خُدا نے فرمایا کہ دیکھو یہ میرا گھر ہے اور حجر اسود میرے
آستانہ کا پتھر ہے اور ایسا حکم اس لئے دیا کہ تا انسان جسمانی طور پر اپنے ولولہ عشق
اور محبت کو ظاہر کرے.سو حج کرنے والے حج کے مقام میں جسمانی طور پر اس کے گرد
گھومتے ہیں.ایسی صورتیں بنا کر گویا خُدا کی محبت میں دیوانہ اور مست ہیں.زینت دُور کر دیتے ہیں.سرمنڈوا دیتے ہیں اور مجذوبوں کی شکل بنا کہ اس کے گرد عاشقانہ
طواف کرتے ہیں اور اس پتھر کو خُدا کے آستانہ کا پتھر تصور کر کے بوسہ دیتے ہیں.اور یہ جسمانی دلولہ روحانی تپش اور محبت کو پیدا کر دیتا ہے.اور جسم اس کے گھر کے گرد
طواف کرتا ہے اور سنگ آستانہ کو چومتا ہے اور روح اس وقت محبوب حقیقی
کے گرد طواف کرتی ہے اور اس کے روحانی آستانہ کو چومتی ہے اور اس طریق میں
کوئی شرک نہیں.ایک دوست ایک دوست جاتی کا خط پا کر بھی اس کو چومتا ہے.
Page 325
۳۱۹
کوئی مسلمان خانہ کعبہ کی پرستش نہیں کرتا اور نہ حجر اسود سے مرادیں مانگتا ہے بلکہ
صرف خُدا کا قرار دادہ ایک جسمانی نمونہ سمجھا جاتا ہے وہیں جس طرح ہم زمین پر
سجدہ کرتے ہیں مگر وہ سجدہ زمین کے لئے نہیں ایسا ہی ہم حجر اسود کو بوسہ دیتے
ہیں مگر وہ بوسہ اس پتھر کے لئے نہیں پتھر تو پتھر ہے جو نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے
نه نقصان مگر اس محبوب کے ہاتھ کا ہے جس نے اس کو اپنے آستانہ کا نمونہ
ٹھہرایا " اے
- حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت ایک ویرانہ میں آبادی کی بنیا د رکھی
وہاں اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسمعیل کو بسایا.اس وقت وہاں نہ پانی تھا اور نہ کسی
انسان کا گذر - اس بے نظیر قربانی کا مقصد یہ تھا کہ یہ جگہ آئندہ عالم گیر ہدایت کا مرکز بنے.اسمعیل علیہ السلام کی یہاں بجنے والی نسل سے وہ عظیم الشان نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو جو
وجہ تخلیق عالم ہے جو رحمة للعالمین ہے.جس کی لائی ہوئی تعلیم ساری دنیا کے لئے اور سارے
زبانوں کے لئے ہوگی.پھر با وجود ظاہر ساز و سامان نہ ہونے کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مولا
سے جیسی توقع کی تھی ویسا ہی ظہور میں آیا.خدا نے وہاں غیر معمولی حالات میں پانی مہیا کیا.یہ جگہ آہستہ
آہستہ آباد ہوئی اور بکہ یا مگر کہلائی.یہاں حضرت ابراہیم علیہ السّلام نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی خاطر
بنائے گئے پہلے مکان کے نا معلوم نہ مانوں سے مٹے ہوئے آثار کو تلاش کیا اور اپنے بیٹے کے
ساتھ مل کر اس مکان
کو دوبارہ تعمیر کیا اور اسے " مَثابَةٌ لِلنَّاسِ“ بنانے کے لئے الہ تعالے کے
حضور گڑ کٹر اکمی دعائیں مانگیں.یہی وہ پہلا گھر ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لئے تعمیر کیا گیا تھا.اسی کا نام بیت اللہ بیت الہی.بیت المعمور اور کعبہ ہے.تمام دنیا کے مسلمان اس کی طرف منہ کر کے نما نہ پڑھتے ہیں.غرض یہ گھر یہ
شہر اور اس کے گرد کے مقامات ایسی جگہیں ہیں جہاں اللہ تعالی کے سینکڑوں عظیم الشان نشان ظاہر
ہوئے.جہاں
کا چپہ چپہ یہ گواہی دے رہا ہے کہ جو اللہ تعالٰی کی خاطر قربانیاں دیتے ہیں اللہ ان کو
کبھی ضائع نہیں کرتا.ان شعائر اللہ کی یاد تازہ کرنے اور یہ یقین حاصل کرنے کے لئے کہ وہ پیچھے
وعدوں والا ہے مسلمانوں
کو حکم ہوا کہ وہ کعبہ اور دوسرے شعائر اللہ کی زیارت
کریں اور دیکھیں کہ
خُدا نے جو کچھ کہا تھا وہ کیسے اور کتنے شاندار انداز میں پورا ہوا.- ہر قوم و ملت کا ایک مرکز اتحاد ہوتا ہے جہاں اس قوم کے افراد جمع ہو کہ خدا کی عبادت کرتے
چشمه معرفت روحانی خزائن جلد ۲۳ هنا :
Page 326
۳۲۰
ہیں.اپنے تمدن اور اپنی ثقافت کے اجتماعی آثار دیکھتے ہیں.افراد ملت باہمی تعارف حاصل کرتے
ہیں.ایک دوسرے کی مشکلات کو سمجھتے اور انہیں دور کرنے اور مقاصد کے حصول کے لئے متحدہ کوشش
کرنے کی تدبیریں کرتے ہیں ، جیسا کہ فرمایا :-
وَبِكُل اُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكَا لِيَذْكُرُوا اسم الله...ہر قوم کے لئے ہم نے ایک مرکزہ بنایا ہے.جہاں عقیدت کے جذبات کے ساتھ اپنے.اللہ کو یاد کرنے کے لئے لوگ جمع ہوتے ہیں.اسی تصور کے لئے حج کی عبادت کو نمونہ کا رنگ دیا گیا ہے تاکہ حج کے لئے جمع ہونے والے
مسلمان اکٹھے مل کر اپنے مالک و خالق کے حسن کے گیت گائیں.اس کے فضلوں کا شکریہ ادا کریں
مشکلات دور کرنے کے لئے اس کے حضور عاجزانہ دعائیں مانگیں.دنیا کے کونے کونے میں بسنے والے
مسلمان ایک دوسرے سے تعارف حاصل کریں.اجتماعی ثقافت کی بنیادیں استوار کریں.بارہمی
مشوره اور اجتماعی جدوجہد کے مواقع پیدا کریں.یہ سب اور کئی اور فوائد حج کی حکمت کا حصہ ہیں.مقامات حج
بیت اللہ : ہزار ہا سال گزرے کہ اللہ تعالٰی کے حکم سے ایک ویرانے میں عبادت کے
لئے ایک معبد بنایا گیا تھا.اس کے بنانے والے کے متعلق یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ وہ کون تھا.لیکن یہ امر یقینی ہے کہ وہ معبد قومی اور ملی ہونے کے لحاظ سے دنیا میں سب سے پہلا معبد تھا.عالم الغیب خُدا خود اس کی خبر دیتے ہوئے فرماتا ہے :-
ان اولَ بَيْتِ وَضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِى بِبَكَةُ.نیز فرمایا :
جَعَلَ اللهُ الكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيمًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامِ
غرض کچھ عرصہ تک لوگ اس معبد میں خدا تعالیٰ کا نام لیتے یہ ہے لیکن نا معلوم کیا تغیرات ہوئے کہ
وہ جگہ ویران ہو گئی اور عبادت کرنے والے لوگ پراگندہ ہو گئے.مگر اللہ تعالیٰ کو یہ جگہ پیاری تھی پس
اس نے ارادہ کیا کہ وہ اُسے پھر سے آباد کر سے اور ہمیشہ کے لیئے دنیا کی ہدایت کا مرکز بنائے.چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کی آبادی کے لئے ایک ایسا مصفی انسان چنا جس کی اولاد نے اپنی
نورانی شعاعوں سے آج تک دنیا کو روشن کر رکھا ہے.هر الحج : ۳۵ ه ال عمران : 94
که : مائده : ۱۹۸
Page 327
۳۲۱
ی
شخص ایک بت نساز گھرانے میں پیدا ہوا تھا.وہ عراق کے شہر کریم یا اُڑ کا رہنے والا
تھا.اس کے خاندان کیسے لوگوں کا گزارہ بتوں کے چڑھا دی اور ثبت فروشی پر تھا.والد بچپن میں
فوت ہو گئے تھے اور چچا کی آغوش میں وہ پلا تھا.جس نے اپنے بیٹوں کے ساتھ اُسے بھی
بت فروشی کے کام پر لگایا.حقیقت سے نا آشنا چھا کو یہ معلوم نہ تھا کہ جس دل کو خالق کون و
مکان چن چکا ہے اس میں بتوں کے لئے کیا جگہ ہو سکتی.پہلے ہی دن ایک گاہک جو اپنی عمر کی انتہائی
منزلیں طے کر رہا تھا اور تھا بھی مالدارہ ثبت خریدنے کے لئے آیا.ثبت فروش چچا کے بیٹے خوش
ہوئے کہ آج اچھی قیمت پر سودا ہو گا.بوڑھے امیر نے ایک اچھا سابت پچھنا اور قیمت دینے
ہی لگا تھا کہ اس بچہ کی توجہ اس گاہک کی طرف ہوئی اور اُس نے اُسے سوال کیا کہ میاں بوڑھے !
تم قبرمیں پاؤں ٹکائے بیٹھے ہو تم اس بہت کو کیا کرو گے ؟
اس نے جواب دیا.اسے گھر سے جاؤں گا اور ایک صاف اور مہتر جگہ میں رکھ کہ اس کی
عبادت کروں گا.یہ سعید بچہ اس خیال پر اپنے جذبات کو روک نہ سکا.اس نے بوڑھے سے کہا
میاں ! تمہاری عمر کیا ہوگی ؟ اس نے اپنی عمر بائی اور اس بچہ نے نہایت حقارت آمیز ہنسی
ہنس کر کہا کہ تم اتنے بڑے ہو اور یہ ثبت تو ابھی چند دن ہوئے میرے چچا نے بنوایا ہے.کیا
تمہیں اس کے سامنے سجدہ کر تے ہوئے شرم نہ آئے گی ؟ نہ معلوم اس بوڑھے کے دل پر توحید
کی کوئی چنگاری گری یا نہ گری.لیکن اس وقت اس بت کا خریدنا اس کے لئے مشکل ہو گیا.اور
وہ بہت وہیں پھینک کر واپس چلا گیا.اس طرح ایک اچھے گاہک کو ہاتھ سے جاتا دیکھ کہ
بھائی سخت ناراض ہوئے اور اپنے باپ کو اطلاع دی جس نے اس بچہ کی خوب خبر لی.یہ پہلی تکلیف تھی جو اس پاک باز ہستی نے تو حید کے لئے اٹھائی مگر با وجود چھوٹی عمر اور
کم نیتی کے زمانہ کے یہ سزا جوش توحید کو سرد کرنے کی بجائے اسے اور بھی بھڑ کانے کا موجب ہوئی.سزا نے فکر کا دروازہ کھولا اور فکر نے عرفان کی کھڑکیاں کھول دیں.یہاں تک کہ بچپن کی طبعی سعاد
جوانی کا پختہ عقیدہ بن گئی اور آخر اللہ تعالیٰ کا نور نوجوان کے ذہنی نور پر گھر کیہ الہام کی روشنی پیدا
کرنے کا موجب بن گیا.آخر یہ بچہ ابراہیم کے نام سے دنیا میں مشہور ہوا.یہ عظیم انسان اپنے شہر کے حالات سے
دل برداشتہ ہو کہ وہاں سے نکل اور اپنی بیوی سارہ کے ساتھ عراق سے ہجرت کر کے پھرتے
پھراتے فلسطین آپہنچا اور عرصہ تک اس ملک میں رہا.لیکن ان کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی نہ بیٹا
Page 328
نہ بیٹی.آخر سارہ نے ابراہیم سے کہا کہ ہمارے ہاں اولاد نہیں.میں چاہتی ہوں کہ اس لڑکی کو جو کہ
مصر کے بادشاہ نے ہماری خدمت کے لئے دی ہے تو اپنی بیوی بنا شاید اللہ تعالٰی اس سے
ہمیں اولاد عطاء فرمائے.یہ نیک اور پاک باز عورت در حقیقت شاہ مصر کے خاندان کی ایک
لڑکی تھی اور اس نے ابراہیمؑ کی معجزانہ طاقت کو دیکھ کہ ان کی دعاؤں کے حصول کی غرض سے اُن
کی خدمت کے لئے اُسے ساتھ کہ دیا تھا.اس لڑکی کا نام ہاجرہ نہ تھا.ابراہیم نے اپنی بیوی
کی اس بات کو قبول کر کے ہاجرہ کو اپنے نکاح میں لے لیا.اور خدا تعالٰی نے بڑھاپے میں ابرام
کو ایک لڑکا دیا جس کا نام اُس نے اسمعیل رکھا.یعنی خداوند خدا نے ہماری دعاشن کی.اس بیٹے کی پیدائش پر خدا تعالیٰ نے ابرام کا نام ابراہام کر دیا.کیونکہ اس کی نعمتوں کی فراوانی
اور آسمانی برکت کا وعدہ کیا گیا تھا.اسی ابراہام کا تلفظ عربی زبان میں ابراہیم ہے.اسی وجہ
سے عبرانی لوگ اُسے ابراہام اور عرب
ابراہیم کہتے ہیں.سارہ جنسی خوشی سے ابراہیم کو ہا جو ان کے
میدی بنانے کا مشورہ دیا تھا اس کے بچہ جنے پر کچھ دیگر ہوئی اور اس نے اس طبعی کمزوری کی
وجہ سے ہاجرہ ہے اور اس کے بچہ کو تکلیفیں دینی شروع کیں.ابراہیم کے دل پر یہ صورتحال ناگوالہ
گزری.لیکن بیوی کی سالہا سال کی خدمت اور اخلاص کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ کچھ نہ کہ سکے بلکہ
کہا تو ہی کہ ہاجرہ یہ تمہاری لونڈی ہے تم جس طرح چاہو اس سے سلوک کہ وہ وہ ابراہیم کو کیا
معلوم که یہ سب سامان کسی اور ہی غرض کے لئے ہو رہے تھے اور یہ سب واقعات ابراہیم کی ایک
اور ہجرت کے سلسلہ کی کڑیاں تھیں.انہی ایام میں جب اٹھکیل کچھ کچھدار ہو گئے اور اپنے والد کے ساتھ دوڑ دوڑ کر چلنے لگے
تھے کہ ابراہیم نے ایک خواب دیکھا کہ وہ اسمعیل کو خُدا تعالٰی کے لئے قربان کر رہے ہیں.اس
زمانہ میں انسانوں کی قربانی کا عام رواج تھا اور اُسے خُدا تعالیٰ کے فضل کے حصول کا ذریعہ سمجھا جاتا
تھا.ابراہیم نے بھی خیال کیا کہ اللہ تعالیٰ میر سے اخلاص کا امتحان لینا چاہتا ہے اس لئے جھٹ
اپنے بڑھاپے کی اولاد کو قربان کرنے کے لئے تیار ہو گئے.اور بچہ سے محبت کے ساتھ پو چھا کہ
تیری مرضی کیا ہے.بچہ کو چھوٹا تھا مگر نور نبوت اُس کی پیشانی سے چمک رہا تھا.نیک باپ
کی تربیت کی وجہ سے
گو ابھی مذہب کی باریکیاں نہ سمجھتا ہو لیکن اس قدر جانتا تھا کہ الہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں ٹالنا چاہیئے
وہ بولے جس طرح چاہو اللہ کے حکم کو پورا کرو.باپ نے آنکھوں پر پٹی باندھی اور بیٹے کو ذبح کرنے
Page 329
کے لئے تیار ہو گئے اور اُسے پیشانی کے بل لٹا دیا.مگر خواب کا مطلب در حقیقت کچھ اور تھا اور
اس کی تعبیر کسی اور طرح ظاہر ہونے والی تھی.چنانچہ اس اثناء میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کا الہام
کیا کہ اب ظاہر میں بچہ کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ قرب الہی کے لئے انسانی قربانی کا یہ انداز
ہمیشہ کے لئے منسوخ کیا جاتا ہے.آئندہ یہ قربانی اس رنگ میں قبول ہوگی کہ خُدا کی رضا اور اس
کے دین کی خاطر جان و مال عزت اور وقت کی قربانی دی جائے تاہم اس اقرار کے ظاہری نشان کے
لئے بطور یادگارہ آئندہ ہر سال ذو الحجہ کی دسویں تاریخ کو عمدہ اور قیمتی جانوں کی قربانی دی جائے.بہر حال ان قربانیوں اور دعاؤں کے نتیجہ میں حضرت ابراہیم کو بشارت ملی کہ اس بچہ کی
نسل
کو میں بڑھاؤں گا اور لوگ اس کی نسل کے ذریعہ برکت پائیں گے چنانچہ الہی اشارہ اور حالات
پیش آمدہ کے تحت حضرت ابراہیمؑ اپنی بیوی ہاجرہ اور پیو ٹھے بیٹے استھیلی کو اس جگہ چھوڑ آئے
جہاں آجکل مکہ آباد ہے.قدیم زمانہ میں اس کا نام بلکہ بھی تھا.حضرت اسمعیل اور ان کی والدہ کو
یہاں
آباد کرنے اور اس جگہ کو رونق بخشنے کا اصل مقصد یہ تھا کہ ہمیشہ کی زندگی کے مرکز بیت تحقیق ہے
کو جس کی بنیادیں ریت کی تہوں میں اپنی صدیوں کی تاریخ چھپائے ہوئے تھیں پھر سے تعمیر کیا جائے.غرض یہاں
آباد ہونے کے کچھ عرصہ بعد ارشاد الہی کے تحت حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے میں
کی مدد سے اس گھر کو تعمیر کیا جو قبلہ عالم ہے.کھیہ اور بیت اللہ کے نام سے مشہور و معروف ہے.یہ گھر مسجد حرام کے درمیان میں بنا ہوا ہے.اس پر سیاہ ریشمی غلاف چڑھا رہتا ہے.کعبیہ کی موجودہ شکل مستطیل ہے.شمالاً جنوباً نہ ہم فٹ لمبا اور شرقاً غرباً ۳۳ فٹ چوڑا ہے
اونچائی کا ہم فٹ ہے.خانہ کعبہ کی شمالی دیوار کے ساتھ بشکل کمان کچھ خالی جگہ ہے.اس کے ارد گرد چھوٹی چھوٹی دیوار
ہے لیکن اُوپر چھت نہیں.کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے کچھ عرصہ پہلے جب
قریش نے خانہ کعبہ کی از سر نو تعمیر کی تو چھت کے لئے وافر کڑی نہ مل سکنے کی وجہ سے یہ حصہ بغیر
چھت کے چھوڑ دیا گیا.طواف میں اس حصہ کو شامل کیا جاتا ہے لیکن مسجد حرام میں نماز پڑھتے
ہوئے اگر صرف اس حصہ کی طرف منہ کیا جائے تو نمازہ درست نہیں ہوگی.خانہ کعبہ کا طلائی پر نالہ
میزاب رحمت" عظیم میں ہی گرتا ہے.ل :- سورة الحج : ٣٠
Page 330
۳۲۴
حجر اسود
خانہ کعبہ کے جنوب مشرقی کونہ کے پاس ایک سیاہ رنگ کا پتھر نصب ہے اسے " حجر اسود
کہتے ہیں.اس پتھر کو بہت متبرک سمجھا جاتا ہے.یہ پتھر غالباً شہاب ثاقب کا ایک بہت بڑا ٹکڑا
تھا جو مکہ کے قریب ابو قبیس نامی پہاڑ پر گیا.تعمیر کعبہ کے وقت حضرت ابراہیم اس نمایاں پتھر
کو وہاں سے اُٹھا لائے اور کونے کے پتھر کی تمثیل اور ایک عظیم یادگار کے طور پرا سے اس
دیوار میں نصب کر دیا.اب جو بھی کعبہ کا طواف کرتا ہے اُسے حکم ہے کہ سب سے پہلے وہ اس
یاد گار سپتھر کو بوسہ دے.یہ پتھر اللہ تعالیٰ کے شعائر میں سے ہے اور اس کے قادر مطلق ہونے اور
صادق الوعد ہونے کا ایک خاص نشان ہے اور جس سے پیار ہو اُس سے تعلق رکھنے والی خاص
اشیاء بھی پیاری لگتی ہیں.بھی فلسفہ حجر اسود کو چوسنے کا ہے.ورنہ یہ پتھر اپنی ذات میں نہ کسی
کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ کوئی فائدہ اور نہ مسلمان اسے کسی رنگ میں نافع یا ضار
سمجھتے ہیں..حجر اسود اور باب کعبہ کے درمیان کی شمالی دیوالہ کاحصہ ملت کم کہلاتا ہے.حج کرنے والے
واپسی کے وقت کعبہ کے اس حصہ سے اپنے سینہ کو لگاتے ہیں.جیسے معانقہ کیا جاتا ہے بیت اللہ
سے الوداع اور اس کی آخری زیارت کا یہ ایک والہانہ اندازہ ہے.ركون بمانی
خانہ کعبہ کا جنوب مغربی کو نہ چونکہ یمین کی سمت ہے اس لئے اسے رکن یمانی" کہتے ہیں.طواف کے وقت اس کو نہ کو ہاتھ سے چھونا اور اُسے بوسہ دینا منتخب
مطاف
خانہ کعبہ کے اردگرد سنگ مرمر کا بنا ہوا ایک دائرہ ہے اس جگہ بیت اللہ کے ارد گرد طوات
کرتے ہیں.طواف ایک عبادت ہے جو بیت اللہ کے اردگرد سات چکر لگا کر ادا کی جاتی ہے
Page 331
مقام ابدانیم
۳۲۵
بیت اللہ کے دروانہہ اور ملتزم کے سامنے ایک قبہ (گنبد نما چھوٹی سی عمارت) ہے
اس میں وہ پتھر رکھا ہوا ہے جس پر کھڑے ہو کہ حضرت ابراہیم نے کعبہ کی دیواریں چنیں تھیں.اسی جگہ کو جہاں پتھر رکھا ہے " مقام ابراہیم " کہتے ہیں.طواف کے سات چکر لگانے کے بعد دو رکعتیں ادا کرنا واجب ہیں.ان دو رکعت کا در مقام
ابراہیم میں ادا کرنا زیادہ ثواب کا موجب ہے.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :-
زمزم
" وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى ، ل
یعنی ابراہیم کے مقام رکھڑے ہونے کی جگہ کو مصلی (نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ.مقام ابراہیم سے بائیں طرف اور کعبہ سے بجانب مشرق ایک کنواں ہے جو بوجہ پیاس
حضرت اسمعیل علیہ السلام کے ایڑیاں رگڑنے سے بطور نشان نمودار ہوا.یہ کنواں اُس
وقت کی یاد گار ہے اسے زمزم کہتے ہیں.زمزم کا پانی رو بقبلہ کھڑے ہو کر بڑے ادب.حصول برکت کی غرض سے پیا جاتا ہے.مسجد الحرام
خانہ کعبہ کے ارد گرد مستطیل اور کسی حد تک گول کھلے صحن کی وسیع و عریض مسجد ہے جہاں
لوگ دائرہ کے رنگ میں صفیں بنا کر اور بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نمانہ پڑ ھتے ہیں.اسی مسجد
قرآن کریم میں "المسجد الحرام" کہا گیا ہے.جیسے وہ فرماتا ہے :-
فَتَدْخُلُنَّ المَسْجِدَ الْحَرَامَانَ شَاءَ اللهُ آمِنِينَ له
این مسجد کا موجودہ رقبہ ایک لاکھ مربع میٹر سے بھی زیادہ ہے.ارد گر د پتھر کے ستونوں پر گنبد نما
چھتوں والے بر آمد سے بنے ہوئے ہیں.ان برآمدوں میں بھی نمازی کھڑے ہو جاتے ہیں.آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اس مسجد کی شکل و صورت بڑی مختصر اور اس سے بالکل مختلف تھی.- بقره : ۱۲۲ :
:- الفتح : ۱۲۸
Page 332
۳۲۶
صفا و مروه
مگر میں مسجد حرام کے قریب جنوب کی طرف دو چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں تھیں.اب
کچھ ہموار ہو کر
دالان اور چبوترے کی شکل میں ہیں مسجد حرام سے نکلیں تو پہلے صفا پہاڑی آتی ہے.اس کے بعد
مشرق کی طرف ہٹتے ہوئے مروہ کی پہاڑی ہے.حضرت ہاجرہ نے پانی کی تلاش اور گھبراہٹ
کے عالم میں ان پہاڑیوں کے سات چکر لگائے تھے کبھی وہ صفا پر چڑھتیں اور کبھی کروہ کی
طرف بھاگ کہ جاتیں اور پھر صفا کی طرف آجاتیں.اسی اضطراری کیفیت اور اس کے نتیجہ میں
ظاہر ہونے والے اللہ تعالیٰ کے فضلوں کی یاد میں حج اور عمرہ کرنے والوں کو حکم ہے کہ وہ صفا
اور مروہ کے بھی سات چکر لگائیں اس عبادت کو سعی بین الصفاء المروہ کہتے ہیں.اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے :-
NNWALA GLAND GE مِن شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أوِ اعْتَمَرَ
فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّونَ بِهِمَا - له
صفا اور مروہ یقینا اللہ کے نشانات میں سے ہیں سو جو شخص اس گھر یعنی کھیہ) کا حج یا
عمرہ کرے تو اُسے اُن کے درمیان تیز چلنے پر کوئی گناہ نہیں.مکہ سے باہر کے مقامات
منی : - محمد سے مشرق کی طرف تین میل کے فاصر بیا ایک وسیع میدان ہے اس میدان میں ہی وہ
تین مچھر ہیں جن کا نام جمرہ یا شیطان مشہور ہے.ان تین پتھروں کے نام یہ ہیں :.جَمْرَة الأولى - جَمْرَةُ الوسطى - جَمْرَةُ العقبه.-
مزدلفہ سے واپس آکر ۱۰ - ۱۱ - ۱۲ - ۱۳ ذوالحجہ کو ان جمرات کو کنکریاں ماری جاتی ہیں جسے
و رحی الجمار" کہا جاتا ہے.حج کرنے والے ، ذو الحجہ کو مکہ سے منی میں آجاتے ہیں.یہیں اس
دن کی ظہر عصر مغرب اور عشاء کی نمازیں پڑھتے ہیں.9 ذوالحجہ کی فجر بھی نہیں ادا ہوتی ہے.اسی
میدان کے ایک حصہ میں وہ عظیم قربان گاہ ہے جہاں حضرت ابراہیمؑ اور حضرت اسمعیل کی قربانی
کی یاد میں ہر سال لاکھوں جانور ذبح ہوتے ہیں.اللہ تعالی نے اس قربانی کی تاریخی اہمیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا :-
:- بقره: ۱۵۹ :
Page 333
۳۲۷
وفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ہے اور ہم نے اس یعنی آنکھیں، کا فدیہ ایک بڑی قربانی کے ذریعہ دیدیا.حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدَى مَعِلَّهُ ه جب تک کہ قربانی اپنے مقام پر نہ پہنچے ؟
میں محل سے مراد منی کا یہی مقام ہے.عرفات :-
مکہ سے شمال مشرق کی طرف قریب و میل کے فاصلہ پر وہ عظیم الشان میدان جہاں 9 ذو الحجہ کو
حب حاجی جمع ہوتے ہیں.اس میدان کو عرفہ یا عرفات کہتے ہیں.ظہر کے وقت سے لیکر سورج
غروب ہونے تک یہاں قیام کیا جاتا ہے جیسے وقوف عرفہ کہتے ہیں.اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں
فرماتے ہیں :.فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَتٍ فَاذْكُرُوا اللهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْعَرَامِ : له
پھر جب تم عرفات سے کو ٹو تو مشعر الحرام کے پاس اللہ کا ذکر کرو.ثُمَّ انتضُوا مِنْ حَيْثُ رَنَاضَ النَّاسُ : له
اور جہاں سے لوگ دواپس، کوٹتے رہے ہیں وہیں سے تم بھی واپس کوٹو.جبل الرحمت بھی اسی میدان کی ایک پہاڑی کا نام ہے.مزدلفہ:
عرفات سے بجانب منی تقریباً تین میل کے فاصلہ پر ایک میدان ہے.مشعر الحرام جو ایک
پہاڑی ہے وہ بھی اسی میدان میں ہے.عرفات سے واپسی پر حج کرنے والے اس میدان میں
رات بسر کرتے ہیں اور یہیں مغرب اور عشاء کی نمازیں جمع کر کے پڑھتے ہیں.ارذو الحجہ کی فجر
کی نماز بھی یہیں ادا کرنی ہوتی ہے.نما نہ فجر کے بعد مشعر الحرام کے پاس جا کہ بکثرت ذکر الہی کرنے
کا حکم ہے.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :-
فَاذْكُرُوا اللهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الحَرَامِ
مشعر الحرام کے پاس اللہ کا ذکر کرو.مواقیت :
مواقیت میقات کی جمع ہے.میقات سے مراد وہ جگہ ہے جہاں یا اس کے قرب وجوانہ اور
محاذ میں اکناف عالم اور دور درانہ کے علاقوں سے حج کی نیت سے مکہ آنے والے احرام باندھتے
ہیں.اور ان مقامات سے آگے احرام باندھے بغیر جانا منع ہے.احترام سے مراد ایک خاص
کی ہے :- ه صفت: ۱۰۸ که : بقره: ۱۹۷ که بقره ۱۹۹ که بقره : ۱۹۷ که بقره ۱۹۹ که بقره ۲۰۰ که بقره ۱۹۹
Page 334
۳۲۸
طریق سے حج یا عمرہ کی نیت کرنا ہے.مختلف علاقوں کے لئے مختلف میقات ہیں جن کی تفصیل یہ ہے :-
ذوالحلیفہ
مدینہ سے قریبا پانچ میل کے فاصلہ پر بطرف مگر ایک گاؤں ہے.مدینہ یا اس طرف سے حج
کے ارادہ سے آنے والے یہاں پہنچ کر احرام باندھتے ہیں.احرام باندھے بغیر اس جگہ سے
آگے بڑھنا درست نہ ہوگا.تحف
-:
مکہ سے بجانب شمال قریبا چالینی میل کے فاصلہ پر ایک مقام ہے جو مصر شام اور مغرب یعنی
شمالی افریقہ کی طرف سے آنے والوں کا میقان ہے.ذات العرق :-
مکہ سے قریب تیس تیل کے فاصلہ پر ایک پہاڑی گاؤں ہے جو عراق اور خشکی کے راستے
مشرقی علاقوں کی طرف سے آنے والوں کا میقات ہے.قرن منازل -: -
مکہ سے اندانہا تیس چالیس میل دور مشرق کی طرف ایک پہاڑ ہے.نجد کی طرف
آنے والوں کے لئے یہ میقات ہے.يَدَمْلَمْ
مگر سے جنوب کی طرف اندازہ انتیس میل کے فاصلہ پر سمندر کے اندر اٹھی ہوئی ایک
پہاڑی کا نام ہے یمن کی طرف سے آنے والوں کے لئے یہ میقات ہے.پاکستان کی طرف
سے بذریعہ بحری جہا نہ جانے والوں کا بھی یہی میقات ہے
جو لوگ ان مقامات کے اندر مکر کے قریب رہتے ہیں.ان کا میقات ان کی جائے رہائش
ہے یعنی وہ گھر سے ہی احرام باندھ کر چلیں.ه : هُوَ مَوْضِعُ مَاءٍ لِبَنِي جَشَم : ٥٢ : - هِيَ تَرْيَةٌ بَيْنَ مَكَهُ وَالْمَدِينَةِ يَقْرُبُ
مِنْهَا القَرْيَةُ الْمَعْرُوفَة بِرَابِعَ : : - هِيَ قَرْيَةٌ عَلَى مَرْحَلَتَيْنِ مِنْ مَكَة.ه: - هُوَجَبَلُ مُشْرِقٌ عَلَى عَرَفَات : ه: - هُوَ جَبَلُ مِنْ جِبَالِ تهامه :
Page 335
۳۲۹
حج کے ارادہ سے مگر جانے والا گھر سے بھی احرام باندھ سکتا ہے.یہاں تک کہ مکہ کے
رہنے والے مکہ کے اندر ہی احرام باندھ سکتے ہیں.یہ ضروری نہیں کہ وہ کسی میقات کے پاس
جاکر وہاں سے احرام باندھیں.میقات کا مفہوم صرف یہ ہے کہ یہاں سے آگے مکہ کی طرف احرام باندھے بغیر جانا منوع اور
طریق حج کے خلاف ہے.مکہ کے قریب ایک جگہ ہے.مگر میں رہنے والوں کے لئے یہ میقات ہے.یعنی اگر کوئی شخص مگر
میں رہ رہا ہو اور عمرہ کرنے کو اس کا دل چاہے تو مکہ سے باہر تنعیم آجائے اور پھر وہاں سے عمرہ
کا احرام باندھ کہ مکہ میں داخل ہوتا کہ عمرہ کرنے کے لئے بھی ایک گونہ سفر کی شرط پوری ہو جائے.حدیث میں ہے :
اِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ انْ
يُعَمِّرَ عَائِشَةَ مِنَ التَّنْعِيمِ
حج اور عمرہ کی عبادت کا ایک حصہ اللہ تعالیٰ کی خاطر مسافرت اختیار کرنا اور اپنے شہر سے باہر
نکلنا بھی ہے.حرم
مگر اور اس کے ارد گرد کا علاقہ حرم کہلاتا ہے.حرم کی حدود مختلف اطراف سے مختلف ہیں.ایک طرف سے مکہ سے قریبا تین میل دوسری طرف سے سات میں تیسری طرف سے نومیل بجانب
جدہ حرم کی حدیں ہیں.حدود حرم کے اندر شکار کھیلنا کیسی جنگلی جانور کو پریشان
کرنا - خود رو ہری گھاس یا خود رو درخت
١١٢
: هُوَ مَكَانَ يُسَمَّى بِمَسَاجِدِ عَائشه : ه: - ترمذی کتاب الحج باب العمرة من التنغيم ص :
سے مکر کی شمالی جانب تنعیم تک کچھ کلو میٹر مکہ کی جنوبی جانب آضاء تک ۱۲ کلومیٹر، مکہ کی مشرقی جانب جعرانہ تک ۱۹ : -
کلومیٹریکر کی مغربی جانب شمیسی تک ۱۵ کلومیٹر مکہ کی شمال شرقی جانب دادی نخلہ تک ہم کلومیٹر موجودہ حد بندی بیان کی جاتی ہے.
Page 336
کاٹنا منع ہے.البتہ موذی جانور مثلاً خونخوار درندہ.سانپ بچھو فصلوں کو نقصان پہنچانے والا
توا - چیل.چوہا اور باؤلے کتے کو مار سکتے ہیں.اذخر نامی گھاس اور خود کاشتہ فصل کاٹ
سکتے ہیں.اوقات حج
حج کے لئے خاص مہینے مقرر ہیں جنہیں " اشهر الحج " یعنی حج کے مہینے کہا جاتا ہے اللہ تعالٰی
قرآن کریم میں فرماتا ہے :-
الحَم اشْهُرُ مَّعْلُومَاتٌ : فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَتَ
وَلا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ في الحج طله
حج کے مہینے دست کئے ، جانے بوجھے ہوئے مہینے ہیں.پس جو شخص ان میں بچے کا ارادہ پختہ کر لے
را سے یادر ہے کہ حج کے ایام میں نہ تو کوئی شہوت
کی بات نہ کوئی نا فرمانی اور نہ کسی قسم کا جھگڑا
کرنا جائزہ ہوگا.یه شوال - ذو القعد اور ذوالحجہ تین ماہ ہیں.ان کو اشعر الحج اس لئے کہتے ہیں کہ ان میں حج کی
تیاری.اخلاق کی درستگی اور حج کے دوسرے احکام مثلاً احترام وغیرہ عملی ارکان کا آغا نہ ہوتا ہے حج
کے آخری مناسک ذوالحجہ کی ۱۳ تاریخ تک ادا کرنے ہوتے ہیں.البتہ طواف افاضہ جسے طواف
زیادہ بھی کہتے ہیں.دس ماہ ذوالحجہ سے ہے کہ آخر ماہ تک ادا کیا جا سکتا ہے.حج فرض ہونے کی شرائط
مسلمان ہو.عاقل بالغ ہو.اتنا مالدار ہو کہ گھر کے خرچ اخراجات کے علاوہ مناسب زاد راہ
پاس ہو.جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے :-
وَتَزَودُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى :
یعنی سفر کے مصارف کے لئے وافر رقم موجود ہو اور تندرست اور سفر کے قابل ہو.راستہ
پر امن ہو.مگر جانے میں کوئی روک نہ ہو.:- البقره : ۱۹۸
:- البقره : ١٩٨
Page 337
۳۳۱
ارکان حج
حج کے تین بنیادی رکن ہیں :-
وز) احترام یعنی نیست باندھنا.(ii) وقوف عرفہ - یعنی نوذو الحجہ کو عرفات کے میدان میں ٹھہرنا.(1) طواف زیارت جیسے طواف افاضہ بھی کہتے ہیں یعنی وہ طواف جو وقوف عرفہ کے بعد
دس ذو الحجہ یا اس کے بعد کی تاریخوں میں کیا جاتا ہے.نور والحجہ کو اگر کوئی شخص عرفات کے میدان میں خواہ تھوڑی دیر کے لئے ہی سہی نہ پہنچ سکے
تو اس کا حج نہیں ہو گا.پھر اگلے سال نئے احرام کے ساتھ اُسے دوبارہ حج کرنا ہوگا.حج کرنے کا طریق
جب انسان مالدار تندرست اور سفر کے قابل ہو اور راستہ پر امن ہو تو اس پر حج فرض
ہو جاتا ہے.جب وہ حج کے ارادہ سے جانے لگے تو تمام رشتہ داروں اور دوستوں سے راضی خوشی
رخصت ہو.اور واپسی تک، اپنے بال بچوں کے لئے ضروریات زندگی کا بندوبست کر جائے.احرام
جب میقات مثلاً علم کے پاس پہنچے تو وضوء کرے یا نہائے.خوشبو لگائے.دو صاف بے کلی
چادریں پہنے.ایک بصورت تہہ بند باندھے اور دوسری بصورت چادر اوڑھے.سر ننگا رکھے.مرد کے لئے حکم ہے.عورت اُسی لباس میں جو اس نے پہن رکھا ہے حج کر سکتی ہے.البتہ عام حالات
میں احرام کے بعد اپنا منہ نگا ر کھے اس پر نقاب نہ ڈالے.سوائے اس کے کہ کسی نامحرم کا آمنا
سامنا ہوا اور اس سے پردہ کرنا ضروری ہو جائے.اس کے بعد مرد ہو یا عورت وہ دو رکعت نفل پڑھے اور پھر حج کی نیت کرتے ہوئے مندرجہ
ذیل الفاظ کہے:-
لبيك اللهُمَّ لَبَّيْكَ - لَبَّيْكَ لا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ
والنعمة لك والمُنكَ لَكَ لا شَرِيكَ لكَ له
: حج کی نیت کیلئے گو منہ سے کچھ کہنا ضروری نہیں لیکن اگر کوئی زبان سے بھی نیت کے الفاظ ادا کرے تو کر سکتا ہے عربی کے
Page 338
۳۳۲
میں حاضر ہوں اسے میرے رب تیرے حضور میں حاضر ہوں.تیرا کوئی شریک نہیں.میں حاضر ہوں.حمد و ثناء کا تو ہی مالک ہے.تمام ملک تیرا ہے.تیرا کوئی شریک
نہیں.یہ عربی الفاظ
تلبیہ کہلاتے ہیں.تلبیہ احترام کا ضروری حصہ ہے.اگر یہ الفاظ حج کے ارادہ کے
ساتھ نہ کہے جائیں تو احرام مکمل نہیں ہو گا.گویا مج شروع کر نے کے لئے تلبیہ کی بالکل دہی حیثیت
ہے جو نماز شروع کرنے کے لئے تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہنے کی ہے.قطبیہ کے بعد انسان محرم ہو جاتا ہے.یعنی حج کے مناسک اور احکام بجالانے کے قابل ہو جاتا ہے
محرم کو بہت سی ایسی باتوں سے بچنا پڑتا ہے جو عام حالات میں اس کے لئے جائز ہیں.مثلاً خشکی
کا شکار کرنا.یا کسی سے کروانا - خوشبو پاتیل لگانا.کنگھی کرنا.بال کٹوانا.ناخن کاٹنا.مرد کے لئے قمیض
یا سلا ہوا کپڑا پہننا سر اور چہرہ ڈھانکنا.پگڑی باندھنا یا ٹوپی پہننا.موزے یا فل بوٹ استعمال
کرنا.بیوی سے مباشرت کرنا یا اُس کے مقدمات کا ارتکاب کرنا جیسے بوسہ لینا وغیرہ.غرض ایسے
تمام امور سے اجتناب لازمی ہے.جو آسائش اور آبرام کی زندگی کا لازمہ ہیں.احرام کی حالت میں فسق و فجور اور جنگ و جدال بہت مذموم حرکات ہیں.عام حالات میں
بھی ایک مسلمان سے ایسے افعال شنیعہ کی اُمید نہیں کی جاسکتی چہ جائیکہ خُدا کے گھر کی زیارت
کی نیت سے جانے والا اس قسم کی حرکات کا مرتکب ہو.اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے :-
ذَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَتَ وَلَا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ -
پس جو شخص ان میں حج کا ارادہ پختہ کر لے را سے یاد ہے) کہ حج کے ایام میں نہ تو کوئی شہروت
کی بات نہ کوئی نا فرمانی اور نہ کسی قسم کا جھگڑا کرنا جائز ہوگا.احرام کے بعد بکثرت تلبیہ کہا جائے.چلتے پھرتے.اُٹھتے بیٹھتے.بلند جگہ پر چڑھتے ہوئے اور
نیچے اترتے ہوئے بالالتزام تلبیہ کہے.تکبیر - ذکر الہی.استغفار اور درود شریف پر زور د ہے.جب مکہ کے قریب پہنچے اور کعبتہ اللہ نظر آئے تو تلبیہ اور تکبیر کہتے ہوئے نہایت درد اور
توجہ کے ساتھ اپنے نیک مقاصد کے لئے دعا مانگے.قبولیت دعا کا یہ خاص وقت ہے لیے
ه : سورة البقره : ۱۹۸ : نیل الاوطار باب رفع اليدين اداء في البيت ٣٤٠٢٥
Page 339
۳۳ سال
جب مکہ میں داخل ہو تو سامان وغیرہ رکھ کر اور وضو یا غسل کر کے سیدھا مسجد حرام میں
جائے.تکبیر اور تلبیہ کہتے ہوئے حجر اسود کے سامنے کھڑا ہو جائے اور جس طرح سجدہ میں ہاتھ رکھتے
ہیں.اس طرح کعبہ کی دیوار پہ ہاتھ رکھتے ہوئے حجر اسود کو چومے اور اگر قوم نہ سکے تو اپنے ہاتھ سے
اُسے چھوٹے.اور اگر چھو بھی نہ سکے تو چھڑی یا ہاتھ سے اشارہ کر کے اُسے چوم ہے.دھینگا مشتی
کر کے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کہ ہے.حجر اسود کو اس طرح بوسہ دینے کو استلام کہتے ہیں.استلام کے بعد طواف شروع کر سے یعنی حجر اسود کی دائیں جانب جدھر دروازہ ہے اس کی طرف
چلتے ہوئے بیت اللہ کے سات چکر لگائے.حیم بھی کعبہ کا حصہ ہے اس لئے چکر لگاتے ہوئے اس کے باہر سے گزر ہے.پہلے تین چکریں
میں رمل یعنی کسی قدر فخریہ انداز میں کندھے مکاتے ہوئے تیز تیز قدم چلنا مسنون ہی ہے.ہر چکر
میں جب بھی حجر اسود کے سامنے پہنچے تو اس کا استلام کرے.رکن یمانی کا استلام بھی مستحسن
ہے.ساتواں چکر حجر اسود کے سامنے آکر ختم کرہے.پھر مقام ابراہیم کے پاس آکر طواف کی دو
رکعت پڑھے.مکہ مکرمہ میں پہنچنے کے بعد بیت اللہ کا یہ پہلا طواف ہے جسے طواف القدوم کہتے ہیں
بہر حال اس طواف کے بعد صفا پر آئے اور بیت اللہ کی طرف منہ کر کے اور ہا تھ اٹھا کر
اللہ تعالیٰ کے حضور دعا مانگے.درود شریف پڑھے تکبیر اور تلبیہ کہے پھر یہاں سے مروہ کی طرف
جائے.مروہ پر بھی اسی طرح دعائیں مانگے.یہ اس کا ایک چکر ہوگا.اس کے بعد صفا کی طرف جائے
یہ اس کا دوسرا چکر ہوگا.اس طرح صفا اور مروہ کے سات چکر لگائے.آخری چکر مردہ پر ختم ہوگا.ان سات چکروں کو " سعی " کہتے ہیں کیے
سعی بین الصفا والمروہ کے بعد وہ فارغ ہے.قیام گاہ پر آکر آرام کر سے بازار میں گھومے
پھر سے کوئی پابندی نہیں.اس کے بعد آٹھویں ذو الحجہ کو منی میں جائے.وہیں ظہر عصر مغرب اور
عشاء کی نمازیں پڑھے.نویں کی فجر پڑھ کر مینی سے عرفات کے لئے روانہ ہو.ظہر سے لے کہ مغرب
تک میدان عرفات میں وقوف کر سے ظہر اور عصر کی نمازیں یہیں جمع کر کے پڑھے.نویں ذوالحج کو
میدان عرفات میں وقوف حج کا اہم ترین حصہ ہے.اگر کسی وجہ سے یہ رہ جائے تو اس سال حج نہیں ہوگا.دادی عرنہ جو عرفات کے پہلو میں ہے اُسے چھوڑ کر عرفہ کا سارا میدان مؤقف ہے ظہر اور عصر
ه تندی کتاب الحج باب الريل من الحجرالى الحجر مثنا ، كشف الخمر ص: ۲ - سورة البقره: ۲۱۵۹
: ابن ماجہ کتاب الحج باب الموقوف بعرفات ص :
Page 340
۳۳۴
کی نماز سے فارغ ہو کر حج کرنے والا تلبیہ و بکبیر - ذکر الہی.استغفار اور دعا میں مشغول رہے.جب سورج غروب ہو جائے تو شرفات سے چل کر مزدلفہ میں آجائے.وادی کو چھوڑ کر
مزدلفہ کا باقی سارا میدان مؤقف ہے.یہاں عشاء کے وقت میں مغرب و عشاء کی نمازیں جمع
کر کے پڑھے.صبح کی نماز بہت سویر سے پڑھی جائے.اس کے بعد شعر الحرام کے قریب جا کر
ذکر الہی کرے.تکبیر اور تلبیہ پر زورد سے جب کچھ روشنی ہو جائے تو مزدلفہ سے چل کر واپس منیٰ
میں آجائے.راستہ سے ستر کنکریاں اٹھا ہے.جب منی پہنچے تو سب سے پہلے جمرة العقبة
کو رمی کرے.یعنی عقبہ نامی ٹیلے کو اللہ اکبر کہتے ہوئے سات کنکریاں مار سے پہلی کنگری کے ساتھ
بار بار تلبیہ کہنے کا وجوب ختم ہو جائے گا.اس کے بعد اگر اس کا ارادہ قربانی دینے کا ہے تو تاریکی
جا کہ قربانی ذبح کرے لیے ورنہ اپنے بال کٹوا کر یا منڈوا کر احرام کھول دے.بال کٹوانے یا
ا
منڈوانے کو احرام کھولنا یا حلال ہونا کہتے ہیں.عورت احرام کھولنے کے لئے اپنے سر کی ایک
دو مینڈھیاں قینچی سے کاٹ دے.اُس کے لئے سارے بال کٹوانا یا منڈوانا جائز نہیں.یہ دسویں
ذوالحجہ کا دن ہے.حجاج کے لئے اس دن عید کی نمازہ نہیں ہے.بہر حال احرام کھولنے کے بعد دسویں
ذی الحجہ کو حج کرنے والا مینی سے مکہ آکر بیت اللہ کا طواف کرے.یہ طواف بھی حج کا بنیادی رکن
ہے.اس کو طواف زیارت اور طواف افاضہ کہتے ہیں.طواف زیارت کے بعد حج کر نیو الے
کے لئے وہ سب اشیاء جائز ہو جاتی ہیں جو احرام کی وجہ سے اس کے لئے منوع تھیں.طواف زیارت سے فارغ ہو کر وہ پھر واپس مٹی میں چلا جائے اور تین دن یہیں مقیم رہے.منی میں تین جمبرے ہیں.جمرۃ الاولی - جمهرة الوسطی - جمرۃ العقبہ.یہ جمھرے جو پہلے چھوٹی چھوٹی
چھا نہیں تھیں اب مبر جیوں کی شکل میں ہیں.کیسے
گیارہویں ذوالحجہ کو حج کرنے والا زوال کے بعد تینوں جمروں کو رمی کر ہے.سب
اس جمہرے کو سات کنکر مارے جو مسجد الخیف کے پاس ہے اور جسے جمرۃ الاولی کہتے ہیں.اس
کے بعد اس جمہرہ کو سات کنکر مارے جو اس کے قریب ہے اور جسے جمہرۃ الوسطیٰ کہتے ہیں.آخر میں
تیسرے جمرہ یعنی جمرۃ العقبہ کو سات کنکر مار ہے.آپ
کو یاد ہوگا کہ دسویں کو مزدلفہ سے واپسی کے بعد بھی اس جمرہ کو سات کنکر مارے گئے
تھے.بارہویں ذو الحجہ کو بھی گیارہویں کی طرح تینوں جمروں کو رمی کرے.اس کے بعد اختیار ہے اگر
کوئی چاہے تو تیرھویں تاریخ کو رمی کرنے کے لئے منی میں قیام کرے.اور چاہے تو :-
ه ابن ماجہ کتاب الحج باب الموقوف ہے :- بقره : ۱۹۷ ۳: مائده : ۱۹۸
: :
Page 341
۳۳۵
فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ - له
پھر جو شخص جلدی کر سے (اور) دو دنوں میں رہی واپس چلا جائے ، تو اُسے کوئی گناہ نہیں.کی اجازت سے فائدہ اُٹھاتے ہوئے بارہویں تاریخ کی رمی کے بعد مگر واپس آجائے بہر حال بارہویں
یا تیرہویں کو مکہ آکر واپسی کا طواف کرے.یہ طواف اُن کے لئے ہے جو کہ مکہ کے باشندے نہیں
ہیں.اور گھر واپس آنا چاہتے ہیں.اس طواف کو طواف الصدر یا طواف الوداع " کہتے ہیں.الوداعی طواف سے فارغ ہو کر حج کرنے والا زمزم کا پانی پیئے.دہلیز کعبہ کو چومے.ملتزم پر اپنا
سینہ رکھ کر رو رو کر دعائیں کرے.استمار کعبہ یعنی کھنے کے غلاف کو پکڑ کر اپنے مولی کے حضور اپنے
گناہوں کی معافی مانگے اور اس سے بخشش کی التجا کر ہے.پھر پچھلے پاؤں ہٹتے ہوئے اپنی آخری نگاہ
شوق کعبہ پرڈالے اور واپس آجائے.محمرة
بیت اللہ کے طواف اور سعی بین الصفا والمروہ کا نام عمرہ ہے اس کے لئے مکہ سے باہر کے
مقام سے احرام باندھنا چاہیئے.اس لئے مگر میں رہنے والے لوگ عمرہ کے احرام کے لئے تنعیم
جاتے ہیں اور وہاں سے عمرہ کا احرام باندھ کر مکہ واپس آتے ہیں تاکہ اس عبادت کے لئے ایک
گونه سفر کی شرط پر عمل ہو جائے.عمرہ کے لئے کوئی خاص وقت مقررہ نہیں.سال کے کسی حصہ میں ادا
کیا جا سکتا ہے.البتہ نویں ذو الحجہ سے لے کر تیرہ ذوالحجہ تک ان چار دنوں میں عمرہ کا احرام باندھتا
درست نہیں.کیونکہ یہ حج ادا کر نے کے دن ہیں.عمرہ کے احرام کھو لنے کا بھی وہی طریق ہے جو حج کے احرام کھولنے کا ہے یعنی عمرہ کرنے کے
بعد اپنے سر کے بال کٹواد سے یا منڈواد سے اور عورت ایک دو لیٹیں کاٹ کر احرام کھولے.حج کی اقسام
حج کی تین قسمیں ہیں :.حج مفرد - حج تمتع - حج قران -
- حج مفرد کا طریق وہی ہے جو او پر بھج کرنے کا طریق کے عنوان کے تحت بیان ہوا ہے.-۲- حج تمتع - اللہ تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے :-
فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَرَ مِنَ الْهَدْيِ ، فَمَنْ
: بقره : ۲۰۲
Page 342
۳۳۶
،
لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَثَةِ أَيَّامِ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ
تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ وذيكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِى
الْمَسْجِدِ الحَرَامِط له
پھر جب تم امن میں آجاؤ تو (اس وقت) جو شخص عمرہ کا فائدہ (ایسے) حج کے ساتھ ملا کیا
اٹھائے تو جو قربانی بھی آسانی سے مل سکے دکر دے) اور جو کسی قربانی کی بھی توفیق نہ
پائے (اس پر تین دن کے روزے تو حج رکے دنوں) میں (واجب) ہوں گے اور سات
(روزے) جب رائے مسلمانو!) تم (اپنے گھروں کو واپس رکوٹ) آؤ.یہ پورے دن ہوئے
یہ (حکم) اس شخص کے لئے ہے جس کے گھر والے مسجد حرام کے پاس رہنے والے نہ ہوں.اس آیت میں حج تمتع کا ذکر ہے جس کی تشریح یہ ہے کہ حج کے مہینوں میں سب سے پہلے
صرف عمرہ کا احرام باندھے اور مکہ پہنچ کر عمرہ کرے اس کے بعد احرام کھول دے.پھر آٹھویں
ذوالحجہ یا اس
سے پہلے حج کا احرام باندھے اور اسی طریق کے مطابق حج کرے جو اد پر بیان ہو چکا
ہے.گویا حج کے مہینوں میں پہلے عمرہ کرنا اور اس کے بعد نئے احرام کے ساتھ حج کرنا تشیع
کہلاتا ہے.تمتع کے معنے فائدہ اٹھانے کے ہیں.حج کرنے والا ایک ہی سفر سے دو فائد سے اُٹھاتا ہے
عمرہ بھی کرتا ہے اور حج بھی ادا کرتا ہے رحج مفرد کرنے والے کے لئے دسویں ذو الحجہ کو قربانی ضروری
نہ تھی لیکن حج تمتع کرنے والے کے لئے قربانی ضروری ہے.اس قربانی کو دم تمتع کہتے ہیں.اگر
قربانی نہ دے سکے تو اس کے بدلہ میں دن روزے رکھے ان میں سے تین حج کے دنوں میں یعنی
سات، آٹھ اور نو ذو الحجہ کو.اور سات روزے واپس گھر آ کر پورے کرے.۳ - حج قران اسے کہتے ہیں کہ شروع میں عمرہ اور حج دونوں کا اکٹھا احرام باند ھے یعنی حج اور
عمرہ دونوں کی نیت کرتے ہوئے تلبیہ کہے.اس طرح احرام باندھنے والا جب مکہ پہنچے گا تو سب سے
پہلے عمرہ کرے گا.اسکی بعد احرام نہیں کھولے گا بلکہ اسی احترام کے ساتھ حج کے مناسک بھی ادا کر لیا.اور جس طرح اس نے عمرہ کا اور حج دونوں کا اکٹھا احرام باندھا تھا.اسی طرح دسویں ذوالحجہ کو
دونوں کا اکٹھا ہی احرام کھولے گا.ن : سورة البقرة : 196 : سه : - مثلا یوں کہے - اللهم إني أُرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَيَسِرُ
هُمَا لِى ثُمَّ بَارِكْ لِى فِيْهما - ہدایہ ص ۲ باب القرآن :
Page 343
م السلام
متمتع کی طرح قران کرنے والے کے لئے بھی قربانی ضروری ہے.اور اگر قربانی میسر نہ ہو تو پھر
مذکورہ بالا طریق کے مطابق وہ دس روز سے رکھے.جنایات حج
جنایہ کو تاہی اور قانون کی خلاف ورزی کو کہتے ہیں.حج کے خاص قاعدے اور قانون ہیں
جو شخص ان کی خلاف ورزی کرے گا وہ زیر مواخذہ ہے جس کی تفصیل کتب حدیث و فقہ میں دیکھی
جاسکتی ہے.مختصراً یہاں کچھ کوتاہیوں کا ذکر کیا گیا ہے یہ
۱ - محرم اگر کسی عذر کی بناء پر سلے ہوئے کپڑے پہن سے یا جوئیں پڑجانے کی وجہ سے اُسے
سرمنڈوانا پڑے تو اس کو تا ہی کے تدارک کے طور پر وہ فدیہ ادا کرے.فدیہ سے مراد روزے رکھنا یا غرباء کو صدقہ دینا یا قربانی ذبح کرتا ہے.فَمَن كَانَ
مِنكُمْ مَّرِيضًا اَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ أَوْصَدَقَةٍ
اوَنُسُكِ.تدارک کے لحاظ سے فدیہ کا مفہوم بالکل ویساہی ہے جیسے نمازمیں غلطی کا تدارک سجدہ سہو
کرنے سے کیا جاتا ہے.۲
مجرم اگر شکار کرہ سے تو بطور کفارہ شکار کی مثل پالتو جانور ذبح کرے مثلاً ہرن مارا تو منی کے
مذبح میں بکرایا چھترا ذبح کی ہے.اور اگر شتر مرغ کا شکار کیا ہے تو اونٹ ذبح کرے.اگر
جانور ذبح نہ کر سکے تو چھ مساکین کو کھانا کھلائے.یہ بھی نہ کر سکے تو تین روزے سے رکھے.بدلہ کا فیصلہ سمجھدار اور جانور کی قدر و قیمت جاننے والے دو ماہرین سے کرایا جا سکتا ہے.فرمایا.البقره : ۱۹۷ سے : محرم کے پاس اگر ان سلے کپڑے نہ ہوں اور نہ وہ باآسانی مہیا کر سکتا ہو تو وہ
سے ہوئے کپڑے پہن سکتا ہے.اس صورت میں فدیہ بھی ضروری نہ ہوگا.رَوَى عَن ابن عباس أَنَّ النَّبِي
صلی الہ علی وسلم قال اذاع يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبِسُ السَّرَاوِيلَ وَإِذْ المْ يَجِدَ النَّعَلَيْنِ فَلْيَنسِ الْخَطَيْنِ
واليقطعها اسفل من الكَعْبَينِ - (ابوداود کتاب الحج باب ما يلبس المحرم قد بدا به کتاب الحج حب ) :
149
ه :- عن عبد الله بن معقل قال قعدت الى كعب بن عجرة في هذا المسجد يعني مسجد الكوفة خالية
عن ندية من صيام فقال حملت الى النبي صلى الله عليه وسلم والعمل يتناثر على وجهى فقال ما كنت
الى أن الجهد بلغ بك هذا - اما تجد ثالاً قلت لا قال صم ثلثة ايام او اطعم مينة مساكين
نصف صاع من طعام و احلق راسك فنزلت فى خاصة - انجارى كتاب التفسير باب توله قد کان منکم و
مريضا رو به ازى من رأسه من :
ستة
Page 344
۳۳۸
ياَيُّهَا الَّذِينَ امنوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَانْتُمْ حُرُهُ، وَمَنْ
قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ
بهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْ يَا بَلغَ الْكَعْبَةِ اَوْكَفَّارَةٌ طَعَامُ
مسكِيْنَ اَوْ عَدْلُ ذلِكَ مِيَا مَا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ ، عَنَا اللهُ عَمَّا
b
0
سَلَفَ، وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ ، وَاللهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ.أحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَامًا تَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَ
حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ البَرِّ مَا دُمْتُ حُرُ مَاء وَاتَّقُوا الله الذي
إلَيْهِ تُحْشَرُونَ ، جَعَلَ اللهُ الكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا
للنَّاسِ وَ الشهر ANGUAGE وَالهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ ذلِكَ لِتَعْلَمُوا
انَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ، وَانَ اللَّهَ بِكُلِّ
شَيْءٍ عَلِيمُه اِعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ لا وَانَّ اللَّهَ غَفُورُ
رحِيمه
اسے ایماندار و ! تم احرام کی حالت میں شکار کو نہ مارا کرو.اور تم میں سے جو شخص اسے جان
بوجھ کر مارے گا تو جو چار پا یہ اس نے قتل کیا ہے اسی قسم کا جانورہ اسے بدر میں دنیا ہو گا جس
کا فیصلہ تم میں سے دو عادل انسان کریں گے اور جسے کھیہ تک قربانی کے لئے پہنچایا جانا ضروری
ہوگا اور اگر اس کی طاقت نہ ہو تو کفارہ ادا کرنا ہوگا.یعنی چند مسکینوں کو کھانا کھلانا یا اس
کے برابرہ روز سے برکھا تا کہ وہ (مجرم) اپنے کام کے بدانجام کو بھگتے ہیں جود پہلے گزر چکا ہے
وہ اللہ نے معاف کر دیا ہے اور جو شخص پھر (ایسا ) کو بے گا اُسے اللہ اُس کے جرم کی)
سزا دے گا اور اللہ غالب اور برے کام کی سزا دینے والا ہے.بحری شکار کرنا اور اس کا کھانا تمہار نے اور مسافروں کے فائدہ کے لئے جائز کیا گیا ہے
لیکن جب تک تم احرام کی حالت میں ہو ر اس وقت تک اختگی کا شکارہ تم پر حرام کیا گیا ہے
اور تم اللہ کا تقویٰ اختیار کرو جس کسی حضور میں تمہیں اکٹھا کر کے لے جایا جائے گا.اللہ نے کعبہ
یعنی محفوظ گھر کو لوگوں کی دائمی ترقی کا ذریعہ بنایا ہے اور دنیز، حرمت والے مہینے
اور قربانی (کو) اور جن (جانوروں) کے گلے میں پٹہ ڈالا گیا ہو ان کو بھی، یہ اس لئے (کیا)
ہے کہ تم جان لو کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ ان سب
کو جانتا ہے
: مائده ۱۶ تا ۴۹۹
Page 345
۳۳۹
یاد رکھو کہ اللہ عذاب دینے میں رکبھی سخت ہے.اور اللہ بہت بخشنے والا (اور)
مہربان بھی ہے.احرام کی حالت میں طواف زیارت سے پہلے اگر اپنی بیوی سے مباشرت کر لے تو اس کا حج
فاسد ہو جائے گا اور حج کے لئے اگلے سال آنا پڑے گا.اس سال وہ حج کے بقیہ مناسک ادا تو
کرے گا لیکن اس کا حج ادا نہیں ہو گا.نیز بطور کفارہ اُسے منی کے مذبح میں اونٹ بھی ذبح کرنا
پڑے گا.احصار
حج یا عمرہ کا احرام باندھنے کے بعد اگر کوئی ایسی روک پیدا ہو جائے کہ وہ مکہ جانے اور
حج یا عمرہ کے مناسک ادا کر نے کے قابل نہ رہے مثلاً سخت بیمار ہو جائے یا دشمن آگے جانے
نہ دے تو ایسا محرم " صدی قربانی کا جانور ذبح کر سے اور اس کے بعد احرام کھوئے.یہ مصری حریم
میں ذبح ہونی چاہیئے.اللہ تعالٰی قرآن کریم میں فرماتا ہے :.فَإِنْ أَحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي : وَلَا تَحْلِفُوا
رُؤسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدَى مَحِلَّهُ دل
پھر اگر تم دکسی سب بے حج اور عمرہ سے، روکے جاؤ تو جو قربانی میسر آئے (ذبح کرو)
اور جب تک کہ قربانی اپنے مقام پید نہ پہنچ جائے اپنے سر نہ مونڈو.194:
البقرہ :
Page 346
۳۴۰
متفرق مسائل
جب تک انسان مکہ مکرمہ میں مقیم رہے بیت اللہ کا بکثرت طوات کر سے زیادہ وقت عبادت
اور ذکر الہی اور تلاوت قرآن کریم میں گزار ہے.غار حرا و کی زیارت کی بھی کوشش کر رہے.یہ غار مگر
سے قریب تین میل کے فاصلہ پر پہاڑ کی چوٹی پر ہے.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بعثت سے پہلے
یہاں آکر عبادت کیا کر تے تھے.اس غار میں ہی آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی.غار ثور دیکھنے جا سکے تو وہ بھی دیکھے یہ مکہ سے پانچ میل کے فاصلہ پر ہے.ہجرت کے دوران
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم محر سے نکل کر اسی غار میں تین دن روپوش رہے تھے.قرآن کریم میں اس
غار کا ذکر آیا ہے.فرمایا :-
ثاني ثنين
إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَاك
جبکہ وہ دونوں نمار میں تھے اور جبکہ وہ اپنے ساتھی رایونیکی) سے کہہ رہا تھا کہ کسی گذشتہ
بھول چوک پر غم نہ کرو.اللہ یقینا ہمارے ساتھ ہے.مدینه منوره
مدینہ منورہ میں بھی بہت سے شعائر اللہ میں مسجد نبوی ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار
اقدس ہے.جنت البقیع ہے.اگر استطاعت ہو تو ان شعائر کی زیارت بھی کرنی چاہیئے میسجد نبوی
ه : تو یہ : ۴۰ : شے :.مکہ اور اس کے ارد گرد کا کچھ علاقہ حرم کہلاتا ہے.اسی طرح مدینہ اور
اس کی ارد گرد کے علاقے زیادہ میل کے قریب غیر سے لیکر تو تہ تک) حریم ہیں.ان إِبْرَاهِيمَ حَمَلَةَ وَإِلَى حَرَّمْتُ المدينة - (ابن ماجہ باب فضل المدينة (۲۳) :
ج عن إلى هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهمان ابراهيم خليلك ونبيك وانك
حرمت مكة على لسمان ابراهيم اللهم وانا عبدك ونبيك والى احرم ما بين لابتيها دراین ناجیہ کما لینا الک
باب فضل المدينه ها ، اللهم ان ابراهيم حرم مكة والى احدهم ما بين لابتيها - (مشكوة ص ۲۳) :
Page 347
میں چالیس فرض نماز ادا کرنا باعث ثواب جزیل ہے.حضور علیہ السلام کے روضہ مبارک کے سامنے
کھڑے ہو کہ درود شریف پڑھنا اور حضور کے عالم گیر اور دائمی فیضان کے لئے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا
کرنا.خاص روحانی کیفیت اور وجدانی کمال کا موجب ہے.اللہ تعالیٰ ہر سچے مسلمان کو ان برکات
سے حصہ لینے کی توفیق بخشے اور وہ جو اللہ تعالیٰ کے گھر اور دوسرے مقامات مقدسہ کی زیارت
سے روکتے ہیں اور خُدا کی وعید سے نہیں ڈرتے.اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور اس ظلم
عظیم سے تو بہ کرنے کی توفیق بخشے.آمین.فتاوى
سوال : - حج کے موقع پر جو رمی جمار کرتے ہیں اس کی کیا مصلحت اور فلسفہ ہے ؟
جواہے :.حج کے اکثر احکام تصویری زبان کا رنگ رکھتے ہیں اور رمی جمار میں یہی حکمت کار فرما
ہے.مثلاً رمی جمار تصویری زبان میں شیطانی قوتوں اور ان کے وسادس سے اظہار بیزاری
اور حملہ آور فاسد خیالات جن سے انسان کو اکثر واسطہ پڑتا ہے کا دفیعہ ہے اس کی ایک مثال
نماز میں بھی ہے جیسے تھی.یعنی لا کے کہتے وقت شہادت کی انگلی اٹھاتے ہیں اور اثبات
کہتے وقت گراتے ہیں.اور حدیث میں آیا ہے کہ یہ رفع سبابہ شیطان جمار کے
یعنی الا ان
لئے تیز نیزہ سے بھی زیادہ کاری ہے.اسی طرح رمی جمار بھی شیطان رجیم سے بیزاری
کی علامت ہے.ایسا ہی نمانہ کے شروع میں اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اُٹھانا
بھی تصویری رنگ رکھتا ہے.حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں :-
" عبادت کے دو حصے تھے ایک وہ جو انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرے جو ڈر نے
کا حق ہے.دوسرا حصہ عبادت کا یہ ہے کہ انسان خدا سے محبت کہ سے جو محبت
کرنے کا حق ہے.یہ حق دو ہیں جو اللہ تعالٰی اپنی نسبت انسانی سے مانگتا ہے.اسلام نے
ان دونوں حقوق کو گورا کرنے کے لئے ایک صورت نماز کی رکھی جس میں خُدا کے.خون کا پہلو رکھا ہے.اور محبت کی حالت کے اظہار کے لئے حج رکھا ہے.حج میں محبت کے سارے ارکان پائے جاتے ہیں بعض وقت شدت
ه مند احمد صا والطبراني في الاوسط :
Page 348
۳۴۲
حج بدل
محبت میں کپڑے کی سیکی حاجت نہیں رہتی.عشق بھی ایک جنون ہوتا ہے.کپڑوں کو سنوار کر رکھنا یہ عشق میں نہیں رہتا.....عرض یہ نمونہ جو انتہا ئے
محبت کے لباس میں ہوتا ہے وہ حج میں موجود ہے.سرمنڈایا جاتا ہے.دوڑتے ہیں محبت کا بوسہ رہ گیا وہ بھی ہے جو خُدا کی ساری شریعتوں میں
تصویری زبان میں چلا آیا ہے.پھر قربانی میں بھی کمال عشق دکھایا ہے.اسلام نے پورے طور پر ان حقوق کی تکمیل کی تعلیم دی ہے.نادان وہ
جو اپنی نابینائی سے اعتراض کرتا ہے" سے
شخص
ایک مرحوم احمدی کے ورثاء نے حضرت کی خدمت میں لکھا کہ مرحوم کا ارادہ پختہ حج پر جانے کا
تھا مگر موت نے جمہلت نہ دی.کیا جائز ہے کہ اب اس کی طرف سے کوئی آدمی خرچ دے کہ بھیج
دیا جاوے؟
فرمایا." جائز ہے.اس سے متوفی کو ثواب حج کا حاصل ہو جائے گا " ہے
سوال: کیا حج بدل کے لئے ضروری ہے کہ حج پر وہی شخص جائے جن کی پہلے خود حج کیا ہوا ہو ؟
جواب: - حج بدل کا جواز مختلف احادیث سے ثابت ہے ان میں سے جو زیادہ صحیح روایات ہیں
ان میں اس شرط کا کوئی ذکر نہیں کہ جو شخص حج بدل کے لئے جائے پہلے اس نے خود اپنا حج کیا
ہوا ہو.یہ حدیثیں بخاری مسلم اور صحاح ستہ کی باقی کتابوں میں مروی ہیں ان میں سے ایک
حدیث یہ ہے :-
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةٌ مِنْ خَتْعَمَ قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ
ان إلى أدْرَكَتْهُ فَرِيضَةُ اللَّهِ فِي الْحَمِ شَيْئًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ
ان يَسْتَوى عَلَى ظَهْرِ بَعِيرِ قَالَ فَحَجَى عَنْهُ - سه
یعنی میرے باپ پر حج فرض تھا لیکن اب وہ اتنا بوڑھا ہو چکا ہے کہ اونٹ پر
:- ملفوظات جلده م٣ ، البدر ١٩٠٣ :
ه - ملفوظات جلد سوئم من :
: - بخاری ومسلم مسلم کتاب
الحج باب الحج عن العاجز......الخ صه :
Page 349
۳۴۳
سہارے کے بغیر سیدھا بیٹھ بھی نہیں سکتا.آپ نے فرمایا تو تم اس کی
طرف سے حج کرو.ائمہ میں سے امام ثوری.امام ابو حنیفہ اور ان کے متبعین ان احادیث کی بناء پر
اس بات کے قائل ہیں کہ حج بدل کے لئے یہ کوئی ضروری شرط نہیں کہ حج پر جانے والا پہلے
خود حاجی ہو.چنانچہ فقہ مذاہب اربعہ میں ہے :-
أَمَّا الْمُرَاهِقُ فَإِنَّهُ يَصِح أن يَجُحَ عَنِ الْغَيْرِ كَمَا يَصِيةُ حَمُ
الْمَرْرَةِ وَالْعَبْدِ عَنْ غَيْرِهِمَا وَكَذَا مَنْ لَمْ يُؤَدِّ فَرِيضَةً
الْحَج عَن نَّفْسِه -
یعنی حنفیوں کا مسلک یہ ہے کہ ایک سمجھدار نو عمر حج بدل کی غرض سے جا سکتا ہے.راسی طرح عورت اور غلام بھی حج بدل کر سکتے ہیں اور ایسا ہی وہ شخص بھی حج بدل کے لئے
جاسکتا ہے جنسی خود حج نہ کیا ہوا ہو.اس کے بالمقابل ابو داؤد - ابن ماجہ یبیقہی.ابن جبان وغیرہ تیسرے درجہ کی کتابوں
میں ایک حدیث ہے جس سے یہ استدلال کیا گیا ہے کہ جو شخص حج بدل کے لئے جائے وہ
پہلے خود حاجی ہو حدیث یہ ہے :-
عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلًا يَقُوا
بيكَ عَنْ شِبْرَمَةَ قَالَ مَنْ شِبْرَمَهُ قَالَ أَخٌ لِي أَوْ قَرِيبٌ لِي
قالَ حَجَجْتَ مِنْ نَفْسِكَ قَالَ لَا قَالَ حَج مَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ
حَج عَنْ شِبُرَمَةَ - ٢
یعنی.ابن عباس نے بیان کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو شبرمہ کی
طرف سے تلبیہ کہتے ہوئے یعنی حج بدل کا احرام باندھتے ہوئے سنا.آپ نے اس سے
پوچھا شہرمہ کون ہے.اس نے عرض کیا میرا بھائی یا عزیز ہے.آپؐ نے پھر پوچھا کیا تم
نے خود حج کیا ہے.اس نے کہا نہیں.آپؐ نے فرمایا.تم پہلے اپنا حج کر د پھر شہرمہ کی
طرف سے حج کرنا.اس حدیث کا مندرجہ ذیل جواب دیا گیا ہے :-
ا، اس حدیث کی دوسری روایت میں فَاجْعَلْ هَذِهِ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ احْجُج
ه : فقہ مذاہب على الاربعہ مثبت :
:- نیل الاوطار ص.
Page 350
۳۴۴
عن شبرمہ کی بجائے یہ الفاظ مروی ہیں ” هَذِهِ عَنْ شِبُرَمَةَ وَحَةٍ
عَنْ نَفْسِكَ " کہ یہ حج تو شہرمہ کی طرف سے ہوا پھر اپنی طرف سے بھی حج کرنا.ان الفاظ سے اس حدیث کا اضطراب واضح ہے اس لئے یہ روایت ان احادیث
کا مقابلہ نہیں کر سکتی جن میں ایسی شرط کا کوئی ذکر نہیں.حج بدل کی حکمت کہ زیادہ سے زیادہ لوگ مقامات مقدسہ اور شعائر اللہ کی زیارت
کے لئے جاسکیں اور بغرباء کو بھی ان برکات سے حصہ پانے کا موقع مل جائے.ایسی
پابندیوں کی متقاضی نہیں ہے.سوال: - کیا بوڑھی عورت زائد از ساٹھ سال غیر محرم کے ساتھ حج کو جاسکتی ہے ؟
جوا ہے :.بوڑھی عورت ایسی عورتوں کے ساتھ حج کے لئے جا سکتی ہے جن کے ساتھ ان کے محرم ہوں
اگر صرف مرد ہی ہوں اور ساتھ کوئی عورت نہ ہو تو پھر حج کے لئے جانے کی اجازت نہیں کئی جوڑیاں
پیش آجاتی ہیں.مثلاً بیماری.موت فوت ہے اور ایسی حالت میں عورت ہی بعض انتظامات
میں حصہ لے سکتی ہے.بہر حال دوسری عورتوں کے ساتھ جانے کی اجازت ہے صرف مردوں
کے ساتھ نہیں.سوال : ایک شخص حج کی نیت سے گھر سے نکلتا ہے براستہ میں فوت ہو جاتا ہے کیا اس کی
طرف سے کسی اور کو حج کرنا چاہیے ؟
جواب : حج کی صحت کا دارو مدار نیت اور عملی کوشش پر ہے جب کسی نے ارادہ کے ساتھ عملی
کوشش بھی کی اور راستہ میں وفات کی وجہ سے ظاہری رنگ میں حج کی تکمیل نہ کر سکا تو خداتعالی
کے حضور اس کا حج ہو گیا اور جو ثواب مقدر تھا وہ اس کو مل گیا.وفات اس کے اپنے
اختیار میں نہ تھی بلکہ خدا تعالیٰ نے یہ تقدیر چلائی.اس لئے اس بناء پر حج کے ثواب سے محرومی
کی کوئی وجہ نہیں ہے.اللہ تعالٰی قرآن کریم میں فرماتا ہے :-
مَنْ يَخْرُجُ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِه
الموتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللهِ - لَه
لا
یعنی جو شخص اپنے گھر سے اللہ تعالیٰ کے حضور جانے کے لئے نکلا اور پھر ا منزل مقصود
تک پہنچنے سے پہلے ہی موت نے اس کو آکیا تو اللہ تعالٰی اُسے اُس کی نیت اور عمل کا ضرور
اجر دے گا.اور اللہ تعالی کے ہاں اُس کا اجر محفوظ ہو گیا.: نساء: 10 :
Page 351
۳۴۵
اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-
مَنْ خَرَجَ حَاجَا اَوْ مُعْتَمِدًا أَوْ غَازِيًا ثُمَّ مَاتَ فِي طَرِيقِهِ
كَتَبَ اللهُ لَهُ اَجْرَ الْغَازِي وَالْحَاةِ وَالْمُعْتَمِرِه
یعنی جو شخص حج یا عمرہ یا جہاد کی نیت سے نکلے اور پھر راستہ میں مر جائے
تو اللہ تعالٰی اس کی نیت اور عمل کے مطابق اُسے غازی - حاجی یا عمرہ کرنے
والے کا ثواب دے گا.رہا دوسرے کو اس کی طرف سے حج کیلئے بھیجوانے کا مسئلہ تو یہ جائز اور باعث
ب ہے لیکن ضروری نہیں.اس بارہ میں علماء حنفیہ لکھتے ہیں :
لا يجب الاحجاج عَنْهُ بِدُونِ الْوَصِيَّةِ " له
یعنی مرنے والے کی وصیت کے بغیر اس کی طرف سے حج کروانا وارثوں پر واجب
اور ضروری نہیں.ہاں اگر وہ وصیت کر جائے اور اس کے ترکہ کے تیسرے حصہ سے
یہ وصیت پوری کی جا سکتی ہو تو پھر وارثوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ اسکی وصیت
کے مطابق کسی نیک متقی کو حج کے لئے مکہ مکرمہ بھجوائیں.سوال : کیا کوئی مسلمان کسی غیرمسلم دوست کی خواہش کے پیش نظر اس کے خرچ پر حج
کر سکتا ہے ؟
جواب : عبادات اسلامی یعنی نماز، روزہ، حج وغیرہ کے فرض ہونے کی بعض شرائط ہیں.اگر
یہ شرائط موجود نہ ہوں تو ان عبادات کا بجا لانا فرض نہیں ہوتا.مثلاً حج کے فرض ہونے کے
لئے مالی استطاعت شرط ہے جس شخص کے پاس مال ہی نہیں اس پر حج بھی فرض
نہیں ہیں ایسے شخص کے فرض حج ادا کرنے کے معنے ہی کچھ نہیں رہتے.رہا نفلی حج کا
ثواب تو یہ ایک الگ صورت ہے جس کا براہ راست اسلام کے اس مخصوص رکن سے
کچھ تعلق نہیں.ہاں شعائر اللہ کی زیارت اور مقامات مقدسہ میں جا کہ دعا کرنے کا ایک
موقع مل جاتا ہے یہ ثواب کے کام تصور میں آسکتے ہیں.لیکن جہاں تک حج کی
فرضیت کا تعلق ہے.فرض اُسی کا ادا ہو گا جس پر حج فرض ہے.پس بنیادی طور پر یہ
سوال ہی غلط ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم کسی مسلمان کو حج کے لئے بھجوائے تو اس کا ثواب مسلمان
کو پہنچے گا یا نہیں.جب اس مسلمان پر چھ فرض ہی نہیں تو فرض عبادت کو بجالانے اور اس
لے : - مشكوة ص ٢٣ : : - تحفة الفقهاء من ٣٣.٥٣ ا
Page 352
۳۴۶
کا ثواب ملنے کے کیا معنے ؟
رہا مقامات مقدسہ کی زیارت کا سوال تو یہ مقصد تو بہر حال مکہ مکرمہ جانے سے
حاصل ہو جاتا ہے اور نیت کے مطابق اس کا ثواب بھی ملے گا.زیارت کرنے والے
کو بھی اس کی نیت کے مطابق اور اس کے لئے پیسے دینے والے کو اس کی نیت اور حالت
کے مطابق.بہر حال اصول یہ ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم بہتر تعلقات اور نیک غرض کے پیش
نظر کسی مستحق مسلمان کو کوئی رقم دے تو اس رقم کو لے لینا اور اس کے خرچ سے اپنے
طریق کے مطابق کوئی عبادت بجالانا مثلاً حج کرنے مکہ چلے جانا مسجد بنوانا یا قرآن کریم یا
کسی اور دینی کتاب کی اشاعت و طباعت میں حصہ لینا منع نہیں.یہ نیک کام کرنے والے
مسلمان
کو اپنی جگہ اس کی عبادت کا ثواب ملے گا اور جس نے نیک تعلقات کے پیش نظر رقم
دی ہے اُسے بھی اس کا اجہ جس رنگ میں اللہ تعالیٰ چاہے گا دے گا.ایک صحابی نہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جاہلیت میں میں نے جو اچھے کام
کئے ہیں کیا اس کا بھی مجھے اجر ملے گا تو آپ نے فرمایا.اسلام قبول کرنے کی سعادت اور
توفیق انہی کاموں کا ہی نتیجہ ہے.حدیث کے الفاظ یہ ہیں :-
عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اَدَ أَيْتَ أَشْيَاءَ
كُنتُ اتَحَنَّتْ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ صَدَقَةٍ رَوْعِنَاتَةِ
وَصِلَةِ رَحْمٍ فَهَلْ فِيْهَا مِنْ أَجْرِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَسْلَمْتُ عَلَى مَا سَلَفَ مِنْ خَيْرٍ له
ر
اسی طرح ایک یہودی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں اپنے سات بہترین
باغ وقف کئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قبول فرمایا.اس کا نام مخبریق
تھا.ان کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : -
مُخَيْرِيقُ سَائِقُ يَهُودَ - لَه
یعنی مخیریق یہود میں سے سب سے آگے جانے والے ہیں.حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے براہین احمدیہ کی اشاعت کے سلسلہ میں ایک سکھ
رنگیس سے چندہ قبول فرمایا.چنانچہ حضور نے اپنے ایک اشتہار مندرجہ براہین احمدیہ
جلد چہارم یہ میں لکھا ہے :-
:
147
ه
:- بخاری :
:- اصابه :
Page 353
"سردار عطر سنگھ صاحب رئیس اعظم لدھیانہ نے کہ جو ایک ہندو رئیس
ہیں اپنی عالی ہمتی اور فیاضی کی وجہ سے بطور امانت سے (۲۵ روپے
بھیجے ہیں.سردار صاحب موصوف نے ہندو ہونے کی حالت میں اسلام
سے ہمدردی ظاہر کی ہے " اے
راسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک ہندو رانی کی نذر اور دعوت بھی قبول
فرمائی.حضور شاء میں دھاریوال کے سفر میں تھے کہ راستہ میں رانی ایشر کو نہ سکنہ
دھام سردار جمیل سنگھ کی بیدہ ہو) کا خاص آدمی پیغام ہے کہ ملا کہ آپ میرے ہاں
قیام فرما دیں.چنانچہ حضرت اقدس نے اس کا پیغام منظور فرما لیا اور وہیں قیام فرما
ئے.....بتھوڑی دیر کے بعد رانی ایشر کو رنے اپنے اہل کاروں کے ہاتھ ایک
تھال مصری کا اور ایک باداموں کا بطور نذر پیش کیا اور کہلا بھیجا بڑی مہربانی فرمائی.میرے واسطے آپ کا تشریف لانا ایسا ہے جیسے سردار جمیل سنگھ آنجہانی کا آنا.حضر
اقدس نے نہایت سادگی اور اس لہجہ میں جو ان لوگوں میں خداداد ہوتا ہے.فرمایا کہ
اچھا آپ نے چونکہ دعوت کی ہے یہ نذر بھی لے لیتے ہیں.۲
سوال : حج بیت اللہ کے منظر کو فلما کہ آج کل سینما میں دکھایا جارہا ہے اس کے متعلق
جماعتی ہدایت کیا ہے؟
جواب :- سینما دیکھنے کے بارہ میں حضرت خلیفتہ المسیح الثانی رضی اللہ تعالی عنہ کا اصولی ارشاد
یہ
، اگر فلم حقیقی مناظر کی ہے تو کوئی اعتراض نہیں.لیکن اگر وہ ایکٹنگ سے
تیار کی گئی ہے تو ا سے دیکھتے کی اجازت نہیں“ سے
(ii) سینما اپنی ذات میں برا نہیں بلکہ اس زمانہ میں اس کی چھ صورتیں ہیں.وہ
محزب
الاخلاق ہیں.اگر کوئی فلم کلی طور پر تبلیغی ہو یا تعلیمی ہواور اس میں
کوئی حصہ تماشہ وغیرہ کا نہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں؟ ہے
تبلیغ رسالت سے : ملفوظات ص : سه : افضل ۲ جولائی شاه : شه : مطالبا تحریک جدید ۳۵ یہ
Page 355
۳۴۹
زكوة
اور
انفاق فی سبیل اللہ
اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے اپنے اموال کو خرچ کرنا جہاں
ایک بہت بڑی نیکی بھلائی اور ملک کی خوشحالی کی ایک یقینی ضمانت ہے وہاں یہ ایک مالی
عبادت بھی ہے.جو قومیں ذخیرہ اندوزی اور مال جمع کرنے کی عادی ہیں اور قومی ضرورتوں اور رفاہ عامہ
کے کاموں میں کھلے دل سے خرچ کرنے سے ہچکچاتی ہیں تباہی اور بربادی ان کے دروازہ
پر کھڑی ہوتی ہیں.فتنہ اور فساد.بدامنی اور انتشار اس ملک کا نصیبہ بن چکا ہوتا ہے جس
میں یہ بخیل قوم بستی ہے.انسان کے پاس جو مال ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے اور اس کی امانت ہے اگر
اللہ تعالی اس امانت میں سے کچھ واپس لینا چاہے اور بندے کو کہے کہ اس کے دیئے ہوئے
مال میں سے وہ اس کی راہ میں خرچ کرے تو خوشی اور پور سے انشراح کے ساتھ اللہ تعالیٰ
کے اس حکم کو مانا اور اس کی راہ میں خرچ کرنا انسان کی مین سعادت اور اس کی مزید
برکات کے مورد بننے کا یقینی اور قطعی ذریعہ ہے.الْخَلْقُ عِمَالُ اللهِ ﷺ کے تحت زعیت کے لحاظ سے سب انسان اللہ تعالیٰ کے
حضور ایک جیسا حق اور درجہ رکھتے ہیں اور دنیا کے تمام اموال میں وہ سب برابر کے
ہیں.تاہم اپنے اپنے وسائل اور استعداد یافت کے لحاظ سے مقدار ملکیت میں وہ
ایک جیسے نہیں ہیں بلکہ حالات کے اعتبار سے کسی کے پاس مال زیادہ ہے اور کسی کے
پاس کم.ایک شخص کمانے کے زیادہ بہتر ڈھنگ جانتا ہے اور دوسرا اس راہ میں
اناڑی اور بے وسیلہ ہے لیکن اس تفاوت کی وجہ سے کمزور بے وسیلہ اور نادار اپنے
: - مخلوق اللہ تعالیٰ کی عیال ہے :
Page 356
۳۵۰
اصل حق سے محروم نہیں ہو سکتا.قرآن کریم کی آیت وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ السَّائِلِ وَالْمُحْرُومِ
الدرلیت: ۲۰) میں اسی حقیقت کی طرف اشارہ ہے پس مالداروں پر فرض ہے کہ ان کے
اموال میں جو دوسروں کا حق ہے وہ بخوشی اور پوری فراخ دلی کے ساتھ اسے ادا کریں.اس
میں ان کی اپنی بھلائی اور ان کی تحویل میں جو مانی ہے اس کی حقیقی حفاظت کا راز مضمر ہے.غرباء اور ناداروں کو یہ حکم ہے کہ وہ دوسروں کے مال کو حرص اور لالچ اور بغض و عناد کی
نیت سے نہ دیکھیں اور نا جائز طریق سے اُسے ہتھیانے اور اس پر زبر دستی قبضہ کرنے کی
راه اختیار نہ کریں.دوسری طرف مالداروں کو یہ حکم ہے کہ وہ معاشرہ کے غرباء اور ناداروں
کا خیال رکھیں اور ضروریات زندگی خوراک - لباس اور رہائش وغیرہ کے مسائل میں انہیں
ایسے حال میں نہ رہنے دیں جو نا گفتہ بہ ہو اور اس میں انہیں تنگی اور وقت کا سامنا کرنا
پڑے.پس اگر امراء اور مالدار یہ چاہتے ہیں کہ غرباء اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو مانیں
جو دوسروں کے مال پر دست درازی نہ کر نے کے بارہ میں انہیں دیا گیا ہے تو ان کا بھی
فرض ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو مانیں اور صدق دل سے اس پر عمل کریں جو ادا کر
دنیا سے غربت اور احتیاج کو مٹانے اور اُسے کم کرنے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے اموال
خرچ کرنے کے بارہ میں دیا گیا ہے.اس وقت دنیا کو کئی معاشی مسائل درپیش ہیں لیکن
ب سے بڑا مسئلہ غیر مساوی تقسیم دولت کا ہے.ایک طبقہ جہاں انتہائی امیر ہے وہاں
ایک طبقہ انتہائی غریب اور خستہ حال ہے.اس غیر طبعی تفاوت کی وجہ سے دونوں طبقوں میں
منافرت اور معاشرت پیدا ہو رہی ہے اور اس طرح ان میں حسد - بغض.کینہ اور انتقام
جیسے مکروہ جذبات بار بار بحرانی کیفیات اور انقلابی شور و شر کا باعث بنتے رہتے ہیں
اور دنیا نے اب تک اس سے نجات نہیں پائی.ایک طرف اگر سرمایہ دارا اپنے وسائل
کے بل بوتے پر کثیر دولت جمع کر رہے ہیں تو دوسری طرف غریب اپنی محسنت فروخت کر نے
کی فکر میں مارے مارے پھرتے ہیں اور ان کی محنت کی صحیح قیمت دینے والا ملنا ان کے
لئے مشکل ہو رہا ہے.امیر و غریب کی اس وسیع خلیج کو پاٹنے کا بہترین ذریعہ انفاق فی سبیل اللہ ہے.انفاق فی سبیل اللہ کی عادت سے یہ احساس اُجاگر ہوتا اور جلد یا تا ہے کہ ہر ایک کو اس کا
صحیح حق ملنا چاہیئے اور کسی کو لوٹ مار یا حق تلفی اور محرومی کا احساس نہیں ہونے دینا چاہیئے.ے.اور ان کے مالوں میں مانگنے والوں کا بھی حق تھا اور جو مانگ نہیں سکتے تھے اُن کا بھی حق تھا :
Page 357
۳۵۱
اسلام نے جہاں انفاق مال
کی پرزور تحریک فرمائی وہاں اس کی غرض بھی متعین کر دی یعنی
خرچ کرنے والے کا مقصد محض رضائے الہی ہو کوئی دنیوی غرض اُس کے پیچھے کارفرمانہ ہو ورنہ
خود غرضی.لالچ.ناجائز کمائی کی حرص اور دوسروں پر احسان جتانے کی بد عادت سے نجات
مشکل ہوگی اور وہ مقصد حاصل نہیں ہو سکے گا جب کسی لئے اپنے مال سے خرچ کرنے کی
اتنے زور کے ساتھ تحریک کی گئی ہے.انفاق فی سبیل اللہ کے نظام کو دوام بخشتے اور بہولت جاری کرنے کے لئے اسلام نے
کفایت شعاری اور تکلف سے پاک سادہ زندگی اختیار کرنے کی تلقین کی ہے اور اسراف
کی راہوں سے بچنے کی ہدایت فرمائی ہے کیونکہ تکلفات کی راہیں بے شمار ہیں اگر انسان
ان میں پڑ جائے تو گنج قارون بھی ناکافی ہے اور جب ذاتی اخراجات اتنے بڑھے ہوئے
ہوں اور انسان تکلفات کا شکار ہو تو انفاق فی سبیل اللہ کے لئے اس کے دل میں کی
بشاشت آئے گی اور اس کے لئے وہ کیسے جرات کر سے گا.انفاق فی سبیل اللہ کی اقسام
اسلامی اصطلاح میں انفاق فی سبیل اللہ کا دوسرا نام صدقات ہے اور صدقات کی
کئی اقسام ہیں مثلاً :-
۱ - قومی اور اجتماعی ضروریات کے لئے مال خرچ کرنا اسکے لئے ضرورت شرط ہے اگر
اجتماعی خطرات منڈلا رہے ہوں اور دینی قیادت مطالبہ کر سے کہ جس کے پاس جو کچھ
ہے وہ لے آئے تاکہ ان خطرات کا مقابلہ کیا جا سکے.تو سب کا فرض ہو جاتا ہے کہ جو
بھی جسکی پاس ہے وہ لاکر پیش کر د سے ارشادِ اللَى إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
انْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ (التوبہ (1) میں اسی حقیقت کی
طرف اشارہ ہے.: لا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ - (الانعام : ۱۳۲)
اور اسراف سے کام نہ لو کیونکہ وہ اسراف سے کام لینے والوں کو پسند نہیں کرتا.ے: ترجمہ : اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانوں اور ان کے مالوں کو (اس وعدہ کے ساتھ خرید
لیا ہے کہ ان کو جنت ملے گی :
Page 358
۳۵۲
۲ - بچت اور زائد از ضرورت مال میں سے خرچ کرنا.اس کی آگے دو قسمیں ہیں :-
الفص :- طوعی جرح جس کی تعیین انسان اپنی مرضی سے کرتا ہے جیسے نفلی صدقات
جنہیں انسان کے اندرونی تقویٰ کے فیصلہ پر چھوڑ دیا گیا ہے.اسی طرح شکرانہ
اداء احسان - تحائف اور معاشرتی تعلقات کی بہتری کے لئے مختلف قسم
کے اخراجات بھی طوعی خرچ میں شامل ہیں.ب : لازمی خرچ جسے ایک مسلمان عمومی لحاظ سے اختیار کرنے کا پابند ہے جیسے
اجتماعی لازمی چندہ جات جو عام ملی نظام اور اشاعت اسلام کے کام کو جاری
رکھنے کے لئے خلیفہ وقت کی طرف سے بلائی گئی مجلس مشاورت نے تجویز
کئے ہوں اور خلیفہ وقت نے ان کی منظوری دی ہو.ج :.حکومت کی طرف سے عائد کردہ محصولات بھی اسی ضمن میں آتے ہیں.د: علاوہ ازیں نفقه اقارب ، حق الخدمت ، صدقة الفطر - ندید
کفارہ اور نذر کے اخراجات بھی لازمی خرچ کئے ہی
حصے ہیں.: اللہ تعالٰی کی راہ میں ایک لازمی حرچ وہ ہے جس کا خصوصی اور اصطلاحی نام
زکواۃ ہے اور اسی خرچ کی تفصیل اس وقت پیش نظر ہے :-
زکواۃ بہت میں سے لازمی خرچ کی اہم ترین قسم ہے کیونکہ یہ وہ کم سے کم انفاق فی
سبیل
اللہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہر صاحب نصاب مسلمان کے لئے ضروری
ہے.معاشرہ کو اس کی ضرورت ہو یا نہ ہو ہر حال میں یہ خرچ لابدی ہے.یہی وجہ ہے کہ زکاۃ
کی ادائیگی اس وقت بھی ضروری ہوگی جب کہ معاشرہ کی تمام قومی اور انفرادی ضرورتیں دوسرے
ذرائع سے باحسن وجوہ پوری ہو رہی ہوں کیونکہ یہ مالی هر چه در اصل اس غرض کیلئے
عائد کیا گیا ہے تاکہ افراد کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی عادت رہے.اکتنازہ بجل
اور حرص کی جڑیں کٹتی رہیں.اور ارشاد ربانی کي لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ
منکم یہ کا مقصد پورا ہو.اور معاشرہ ظالم اور بخیل افراد کی احتیاج سے محفوظ
ہو جائے.-
ے : - الحشر و تر جمہ : یعنی مال تم میں سے مالداروں کے اندر چکر نہ کھاتا پھر سے :
Page 359
۳۵۳
زکواۃ اور انکم ٹیکس میں فرق
-
زکواۃ کے معنے ہیں پاک کرنا بنشو و نما دینا.خوشحالی سے ہمکنار کرنا.اس لحاظ سے جو مسلمان
خداتعالی کی خوشنودی اور اُس کی رضا کی خاطر نہ کواۃ ادا کرتا ہے وہ اپنے آپ کو اکتناز اور
مال جمع کرنے کی حرص سے پاک کرتا ہے.اُس کے مال میں جو دوسروں کا حق ہے وہ ادا
کر کے اپنے مال کو پاکیزہ اور طیب بناتا ہے اللہ تعالی کی برکتوں اور اس کے فضلوں کا وارث
بنتا ہے.غریبوں اور ضرورتمندوں کی ضروریات پوری کر کے امن و آشتی حفظ و امان کے
حالات پیدا کرتا ہے.اس طرح اپنے مال کی حفاظت اس کی تجارت کے فروغ اور صنعت و
حرفت کی ترقی کے لئے راہ ہموارہ کرتا ہے اور سارے ملک کی خوشحالی اور اضافہ دولت
کی ضمانت دیتا ہے.ایک مسلمان زکواۃ کو ایک عبادت سمجھ کر خوش دلی سے ادا کرتا ہے کیونکہ اس کے پیچھے
اللہ تعالٰی کے احسانات کی وجہ سے جذبہ تشکر اور اس کے فضلوں کی امید کار فرما ہوتی ہے
اس کے برعکس انکم ٹیکس کے ادا کرنے میں یہ محرکات بڑی حد تک مفقود ہوتے ہیں اور اس وجہ
سے انسان بعض اوقات اس سے بچنے کے چیلے تلاش کرتا ہے.نیز اس کی شرح کا تعیین چونکہ
بندوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے اس لئے اس میں انصاف کے عناصر ایک حد تک مفقود ہو سکتے
ہیں.اس طرح دونوں طرف بے اعتمادی اور بے اعتباری کے جذبات پیدا ہوتے ہیں.زکواۃ بہت اور جمع شدہ دولت پر لگتی ہے گویا جمع شدہ سرمایہ پر یہ ایک بہترین قسم کا
محصول ہے جس کے نتیجہ مں سرمایہ گردش پر مجبور ہو جاتا ہے اور تقسیم دولت کے رجحان کرد با
اور سرمایہ کاری کو اس سے فروغ ملتا ہے.اس کے برعکس انکم ٹیکس آمدنیوں پر لگایا جاتا
ہے جس کی وجہ سے سرمایہ کاری ایک حد تک رک جاتی ہے.روپیہ جمع کرنے اور دولت
کے انبار لگانے کا جذبہ ترقی پاتا ہے اور روپیہ کی گردش کم ہو جاتی ہے.بے کاری اور
بے روزگاری بڑھ جاتی ہے اور عامۃ الناس کی قوتِ خرید نہ ہونے کے برابر رہ جاتی ہے.لیکن زکواۃ دینے سے معاشرہ کی عملی قوتیں بیدار ہوتی ہیں جو دولت میں اضافہ اور
معاشرہ کی خوش حالی کا موجب بنتی ہیں.
Page 360
۳۵۴
زکواۃ و صدقات کے بارہ میں قرآنی ارشاداتے
اللہ تعالیٰ نے قر آن کریم میں زکواۃ و صدقات کے بارہ میں جو آیات نازل فرمائی ہیں ان
میں سے بعض درج ذیل ہیں :-
- خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَل
-
عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلوتَكَ سَكَنَّ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيم -
اسے رسول ان کے مالوں میں سے صدقہ ہے تاکہ تو انہیں پاک کر سے اور ان
کی ترقی
کے سامان مہیا کر سے اور ان کے لئے دعائیں بھی کرتارہ کیونکہ تیری دُعا ان کی
تسکین کا موجب ہے اور اللہ تیری دعاؤں کو بہت سننے والا اور حالات کو
جاننے والا ہے.۲ - مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ
انَبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُل سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٍ وَاللهُ يُضْعِفُ
لِمَن يَشَاءُ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ - له
جو لوگ اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے اس فعل کی حالت اس
دانہ کی حالت کے مشابہ ہے جو سات بالیں اُگائے اور ہر بالی میں سودا نہ ہو.اور
اللہ جس کے لئے چاہتا ہے اس سے بھی بڑھا بڑھا کر دیتا ہے اور اللہ وسعت
دینے والا اور بہت جاننے والا ہے
٣ - مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالُهُمُ ابْتِغَاء مَرْضَاتِ اللهِ وَتَثْبِيتاً
من أنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةِ بَرَبُوَة أَصَابَهَا وَابِك فَاتَتْ أكُلَهَا
ضِعْفَيْنِ فَإِن لَمْ يُصِبْهَا وَابِكَ نَكِّلُّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
تصدر تو
جو لوگ اپنے مال اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے اور اپنے آپ کو مضبوط
کرنے کے لئے خرچ کرتے ہیں اُن کے خرچ کی حالت اس باغ کی حالت کے مشابہ
ہے جو اونچی جگہ پر ہو اور اس پر تیز بارش ہوئی ہو جس کی وجہ سے وہ اپنا پھل دوچند
لایا ہو اور اس کی یہ کیفیت ہو کہ اگر اس پر ندور کی بارش نہ پڑ سے تو تھوڑی سی بارش
له - التوبه :١٠٣ : ه: - البقرة :۲۶۲ : ۳:- البقرة : ۲۶۶ :
-}
Page 361
۳۵۵
یہی اس کے لئے کافی ہو جائے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے.م.قُلْ إِنَّ رَبّى يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا
يَعْلَمُونَ
تو کہہ دے میرا رب جسکے لئے چاہتا ہے رزق کا دروازہ کھول دیتا ہے اور جب کسی
لئے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے لیکن لوگوں میں سے اکثر جانتے نہیں.۵ - المُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنْتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَا مُرُونَ
بالمَعْرُونِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلوةَ
وَيُؤْتُونَ الزَّكوة وَيُطِيعُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ
سَيَرْحَمُهُمُ
حَمُهُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيم - الآية له
مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں وہ نیک
باتوں کا حکم دیتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں
اور زکواۃ دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں یہ ایسے لوگ
ہیں کہ اللہ ضرور ان پر رحم کرے گا.اللہ غالب اور ٹبری حکمت والا ہے.4 - وَعَدَ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَتٍ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الانهرُ خَلِدِينَ فِيهَا وَ مَسكِنَ.طَيِّبَةٌ فِي جَنَّتِ عَدْنٍ وَ
رضْوَانٌ مِّنَ اللهِ أَكْبَرُ ذَالِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ.اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے ایسی جنات کے وعدے کئے ہیں
جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں وہ اُن میں ہمیشہ رہیں گے اور ہمیشہ رہنے والی جنتوں
میں پاک رہائش گاہوں کا بھی وعدہ کیا ہے اور ان کے علاوہ اللہ کی رضا مندی
سب سے بڑا انعام ہے جو ان کو ملے گا.اور اس کا ملنا بہت بڑی کامیابی ہے..وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنفِقُونَهَا فِى
سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرُهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ، يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا
فِي نَارِ جَهَنَّمَ فتكوى بها جياد
هُمْ هَذَا مَا كَنَزَتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْبَرُونَ
وہ لوگ بھی جو سونے اور چاندی کو جمع رکھتے ہیں اور اللہ کے راستہ میں خرچ
-
ظهور
ے.سیا: ۳۷ : ۵۳:- التوبه : ۲۰۰۱ : ۵۳:- التوبه : ۲ : ۵۲:- التوبر : ۳۵۰۳۴ :
Page 362
۳۵۶
نہیں کرتے ان کو دردناک عذاب کی خبر د ہے.یہ عذاب اس دن ہو گا جب کہ اس
جمع شدہ سونے اور چاندی پر جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی.پھر اس سونے اور
چاندی سے ان کے ماتھوں اور پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغ لگائے جائیں گے
اور کہا جائے گا کہ یہ وہ چیز ہے جس کو تم اپنی جانوں کے لئے جمع کرتے تھے پس
جن چیزوں کو تم جمع کرتے تھے ان کے مزہ کو چکھو.۸ - وَمِنْهُمْ مَنْ عُهَدَ اللهَ لَئِن أَتْنَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّ تَنَ وَ
لَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّلِحِيْنَ - فَلَمَّا شُهُمْ مِّن نَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ
وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ - فَاعْقَبَهُمْ نِفَاقَا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى
يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا اَ خَلَفُوا اللهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا
يَكْذِبُونَ - لَه
اور ان میں سے کچھ افراد ایسے بھی ہیں جو اللہ سے یہ عہد کرتے ہیں کہ اگر وہ اللہ ہمیں
اپنے فضل سے کچھ دے گا تو ہم ضرور اس کی راہ میں صدقہ کریں گے اور ہم ضرور
نیک بن جائیں گے.اور جب اس خُدا نے ان کو اپنے فضل سے مال عطاء فرمایا تو
انہوں نے اس کی راہ میں اسے خرچ کرنے سے بخل کیا اور اپنے پرانے طریقوں
کی طرف لوٹ گئے اور خُدا اور رسول کی باتوں سے روگردانی کرتے ہوئے پیٹھ پھیر
لی پس نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے ان کے دلوں میں اُس دن تک کے لئے جب وہ اس
سے ملیں گے نفاق کا سلسلہ چلا دیا کیونکہ انہوں نے جو خُدا سے وعدہ کیا تھا اس
کی خلاف ورزی کی اور بوجہ اس کے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے.4 - وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُونَ بِمَا أَتَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ
هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَتُونَ مَا يَخِلُوا
به يَوْمَ الْقِيِّمَةِ وَ لِلّهِ مِيرَاتُ السَّمَوتِ وَالْاَرْضِ وَاللهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِير - له
اور جو لوگ اس مال کے دینے ہیں جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دیا ہے بخل
کرتے ہیں وہ اپنے لئے اس کو ہر گنہ اچھا نہ سمجھیں اچھا نہیں بلکہ وہ ان کے لئے بڑا
ہے جن سالوں میں وہ بخل سے کام لیتے ہیں قیامت کے دن یقینا ان کا طوق بنایا
له - التوبه : ۵ تا یه : له :- ال عمران : ۱۸۱ :
Page 363
۳۵۷
جائے گا اور ان کے گلوں میں ڈالا جائے گا.اور آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ ہی
کے لئے ہے اور جو کچھ تم کہتے ہو اللہ اس سے آگاہ ہے.١٠ - الشَّيْطَنُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَوَيَا مُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ ، وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ
مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلَاء وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمُهُ بِهِ
شیطان
تمہیں محتاجی سے ڈراتا ہے اور تمہیں بے حیائی کی تلقین کرتا ہے اور اللہ اپنی
طرف سے ایک بڑی بخشش اور بڑے فضل کا تم سے وعدہ کرتا ہے اور اللہ
بہت وسعت دینے والا اور بہت جاننے والا ہے.1 - وَمَا أَتَيْتُمْ مِنْ رِبَا لِيَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ
اللهِ وَمَا أَتَيْتُم مِّن زَكوة تُرِيدُونَ وَجْةَ اللهِ فَا و ليك
هُمُ الْمُضْعِفُونَ ، له
اور جو روپیہ تم سود حاصل کرنے کے لئے دیتے ہو تا کہ وہ لوگوں کے مالوں میں
بڑھے تو وہ روپیہ اللہ کے حضور میں نہیں بڑھتا اور جو تم اللہ کی رضا حاصل
کرنے کے لئے زکواۃ کے طور پر دیتے ہو تو یاد رکھو کہ اسی قسم کے لوگ خدا کے
ہاں روپیہ بڑھا رہے ہیں
١٣ - رِجَالُ لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلوةِ
وَإِيتَاءِ الزَّكوة من يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلوبُ وَالْأَبْصَارَة
لِيَهُمُ اللهُ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ ط
وَالله يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ٥٣٥
یہ ذکر کرنے والے اللہ کے کچھ ایسے بند سے ہیں جن کو اللہ کے ذکر سے اور نمانہ
کے قائم کرنے سے اور زکواۃ کے دینے سے نہ تجارت اور نہ سودا بیچنا غافل کرتا
ہے وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اُلٹ جائیں گے اور آنکھیں پلٹ
جائیں گی.نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ ان کو اعمال کی بہتر سے بہتر جزا د سے گا اور ان کو
اپنے فضل سے مال و اولاد میں بڑھا دے گا اور اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر
حساب کے رزق دیتا ہے :
:- البقرة : ٢٧٩ : : - الروم : ۴۰ : ے :- النور : ۳۸، ۳۹ :
Page 364
۳۵۸
زکواۃ واجب ہے
اسلام نے روپیہ کھانا منع نہیں کیا ہاں روپیہ کو بند رکھنا اور سورج نہ کرنا نا جائز قرار
دیا ہے تاہم اگر کوئی شخص اپنی آئندہ کی ضروریات کے لئے بطور احتیاط کچھ روپیہ جمع کرتا ہے اور
پڑے پڑھے اس پر سال گزر جاتا ہے تو اس روپیہ پر زکواۃ واجب ہو جائے گی.اسی کی
طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا :-
خُذْ مِنَ امْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمُ.اسے رسول ان کے اموال میں سے زکوۃ وصول کہ اس طرح تو ان کو پاک اور ان
کے تزکیہ کے سامان کر سے گا.اموال زکواة
اموال زکوۃ کی دو قسمیں ہیں.اموال باطنہ اور اموال ظاہرہ.اموال باطنہ یہ ہیں :-
نقد روپیہ.سونا.چاندی خواہ کسی شکل میں ہو.زیورات ہوں یا استعمال کی کوئی اور چیز.اموالے ظاہرہ یہ ہیں :-
الف : موکیشی مثلاً اونٹ گائے بھینس بھیڑ بکری.مبشر طیکہ یہ باہر سرکاری چراگاہوں یا
شاملات دیہہ میں چرتے ہوں اور ان کو گھر میں با قاعدہ چارہ ڈالنے کی ضرورت نہ پڑے ہیے
ہے :.زمین میں پیدا ہونے والی فصلیں جیسے گندم - جو یکی، چاول - باجرہ کھجور - انگور جنگلی شہد
جو کسی نے اکٹھا کیا ہو.سے
:- التوبة : ۱۳ : سه : گھوڑے اور گدھے بھی اموال زکوۃ میں شامل ہیں یا نہیں اور ان کی شرح زکواۃ
کیا ہے.یہ سوال بحث طلب ہے :.یہ سوال بھی بحث طلب ہے کہ دوسری نقد آور فصلیں
مثلا کی اس گنا تیل والے بیج.ربڑ مختلف سبزیات - تربوز - خربوزے سرد ہے.گرمے مختلف پھل مثلاً سیب -
ام مالٹے کنوں میٹھے.کیلا.بادام - اخروٹ پستہ چلغوز سے وغیرہ.اس قسم کی پیداوار پر زکواۃ ہے یا
نہیں اس مسئلہ کو زیر غور لایا جا سکتا ہے اور اصول قیاس سے کام لیکہ کوئی فیصلہ کیا جا سکتا ہے :
Page 365
۳۵۹
A
: وہ معدنیات جو افراد کی تحویل میں ہوں.مثلاً لو ہے کی کان.تانبے کی کان ٹین کی کان -
تیل کے کوئیں وغیرہ.: اموال تجارت - صنعت و حرفت میں لگا ہوا سرمایہ.اموال ظاہرہ سے زکواۃ وصول کرنے کا اصل حق حکومت کو ہے یہی وجہ ہے کہ جن زمینوں
سے حکومت مالیہ وصول کرتی ہے یا حبس تجارتی اور صنعتی کاروبار پر نئم میں گاتی ہے ان پر
مزید زکواۃ نہیں.سوائے اس کے کہ کسی مال پر حکومت کا ٹیکس زکواۃ کی مقررہ شرح سے کم ہو
اس صورت میں جو فرق ہے اُس کے حساب سے اپنے طور پر یا حکومت کے مطالبہ پر بخوشی
زکوۃ ادا کرنا باعث خیر و برکت اور موجب ثواب ہوگا.اموال باطنہ کی نگرانی حکومت کی طرف سے نہیں کی جاسکتی جیسے جمع شدہ نقد روپیہ.زیورات مختلف قسم کے قیمتی جواہر بیش قیمت پتھر لعل - یاقوت و زمرد - ان اموال کی
زکواۃ ادا کرنا ایک سچے مسلمان کی ذاتی ذمہ داری ہے.یہ نہ کواۃ غربا ، مساکین اور مستحقین کو
افراد خود اپنی مرضی سے بھی دے سکتے ہیں اور دینی انجمنوں اور اشاعت اسلام کے مرکزی
اداروں کے ذریعہ بھی تقسیم کر سکتے ہیں.زیادہ بہتر اور ہر لحاظ سے با برکت صورت یہ ہے کہ
اس قسم کی ساری زکواۃ خلیفہ وقت کی خدمت میں بھجوائی جائے تاکہ ساری جماعت کے
غرباء - مساکین اور مستحقین کو اس مال میں سے حصہ مل سکے یہی وجہ ہے کہ تمام علماء
اقت نے یہ اصول تسلیم کیا ہے کہ زکواۃ کی تقسیم امام وقت کا حق ہے.اے
شرائط وجوبے زکوۃ
زمین کی پیداوار مثلاً مختلف قسم کے غلے کھجور.انگور شہد.ان پر اس وقت زکواۃ
واجب ہوتی ہے.جب وہ بر آمد ہوں اور ان کا نصاب مکمل ہو.اس کے بعد یہ پیداوار
خواہ کتنے سال پڑی رہے اس پر زکواۃ عائد نہیں ہوگی.دوسری قسم کے احوال مثلاً نقد روپیہ.سونا - چاندی - اموال تجارت - مولیشی.ان پر
زکوۃ تب واجب ہوگی جبکہ وہ مقررہ نصاب کے برابر ہوں اور سال بھر ملکیت میں رہیں گویا
جتنے سال وہ ملکیت میں رہیں گے ہر سال ان پر زکواۃ واجب ہوگی.: تشريح الزكوة ص :
Page 366
Wy
مویشیوں کے لئے ایک خصوصی شرط یہ بھی ہے کہ وہ باہر سرکاری چراگاہوں جنگلوں اور شاملات
دیہہ میں چرتے ہوں اور اسی پر ان
کا گزارہ ہو.انہیں خود چارہ ڈالنے کی ضرورت نہ پڑتی ہونیز وہ
جو تنے اور لادنے کے کام نہ آتے ہوں.مویشیوں کی زکواۃ دراصل ایسے ممالک اور علاقوں کے ساتھ وابستہ ہے جہاں وسیع چرا گا ہیں
میتر ہیں جن کے سہارے وہاں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں یہ یوڑ اور گلے پائے جاتے ہیں اور
مقصد مال کمانا یا دودھ یا گوشت بر آمد کرنا ہوتا ہے یا اسی قسم کے دوسرے تجارتی اور کاروباری
مقاصد کے لئے بطور پیشہ جانور پالے جاتے ہوں.نصاب زکواۃ اور شرح زکوۃ
نقدی.سونا.چاندی اور دوسرے ہر قسم کے سرمایہ کے لئے نصاب کا معیار چاندی ہے
یعنی جب کسی پاس باون تولہ چھ ماشہ ( یا وہ تولہ چاندی ہو یا اتنار و پیہ یا سونا ہو کہ اس سے اس
مقدار میں چاندی خرید کی جا سکتی ہو تو اس پر زکواۃ واجب ہوگی.شرح زکواۃ پورے
سرمایہ کا چالیسواں حصہ یا اڑھائی (۲) فی صد ہے.مثلاً اگر بادن تولہ چھ ماشہ چاندی کی
قیمت چار صد روپیہ ہے اور اتنی رقم اس کے پاس ہے تو اڑھائی فی صد کے اعتبار سے دنش
روپیہ زکواۃ ادا کرنا ہو گی.یہ وہ اموال زکواۃ ہیں جن کے لئے معیار نصاب چاندی ہے اور نصاب کی مقدار معلوم کرنے کا
ذریعہ وزن ہے.سونے چاندی کا جو زیور عورت کے ذاتی استعمال میں آتا ہے اور وہ کبھی کبھی مانگنے پر غریب
عورتوں کو بھی استعمال کے لئے دے دیتی ہے اس پر زکوۃ نہیں.سید نا حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں :-
جو نہ یو ر استعمال میں آتا ہے اس
کی زکواۃ نہیں ہے اور جو ر کھا رہتا ہے اور کبھی
کبھی پہنا جاو سے اس کی زکواۃ دینی چاہئیے جو زیور پہنا جاوے اور کبھی کبھی غریب
عورتوں کو استعمال کے لئے دیا جائے بعض کا اس کی نسبت یہ فتویٰ ہے کہ اس کی
زکوۃ نہیں.اور جو زیور پہنا جائے اور دوسروں
کو استعمال کے لئے نہ دیا جائے
Page 367
۳۶۱
اس میں زکوۃ دینا بہتر ہے کہ وہ اپنے نفس کے لئے مستعمل ہوتا ہے اس پر ہمارے
گھر میں عمل کرتے ہیں اور ہر سال کے بعد اپنے موجودہ زیور کی زکواۃ دیتے ہیں اور
جو زر اور روپیہ کی طرح رکھا جائے اس کی زکواۃ میں کسی کو بھی اختلاف نہیں " کے
تجارت میں لگے ہوئے سرمایہ پر زکواۃ وصول کرنے کا اصل حتی اگر چہ حکومت کو ہے اور وہ
ٹیکس کی مقدار کا تعین اپنی ضروریات کو مد نظر رکھ کر کرتی ہے تاہم رہنمائی کے لئے علماء
امت نے سرمایہ پر تعیین زکوٰۃ کا جو اصول تجویز کیا ہے اس کا مختصر بیان خالی از فائدہ نہ ہوگا.صنعت و تجارت میں لگے ہوئے سرمایہ میں سے صرف اُسی سرمایہ پر نہ کوہ ہے جو کاروبار
کے چکر میں آتا ہے.یعنی مال منگوانے یا بیچنے کے لئے مال تباہ کرنے پر صرف ہوتا ہے جو
سرمایہ کارخانے کی مشیری - عمارات ضرورت کے دفاتر ، فرنیچر اور حساب کتاب کے
رجسٹروں ہی کھاتوں اور فائلوں پر صرف ہوا ہے اس پر زکواۃ عائد نہ ہوگی.اسی طرح
بیسوں.ٹرکوں ٹیکسیوں اور کیا یہ کے لئے تعمیر کردہ دوکانوں اور مکانوں پر صرف ہونے والا
سرما یہ بھی زکواۃ سے مستثنیٰ ہے.اسی طرح وہ اشیاء جو انسان کی حاجات اصلیہ میں خرچ
ہوتی ہیں مثلا کہ ہنے کا مکان پہننے کے کپڑے گھر کا اثاثہ - فرنیچر آنے جانے کے لئے موٹر
لائبریری کی کتب وغیرہ یہ خواہ کتنی ہی قیمتی ہوں اور لاکھوں روپیہ کی ہوں ان
پر بھی زکواۃ عائد
نہ ہوگی.-
بہر حال چلتی تجارت میں لگے ہوئے سرمایہ پر زکواۃ کا حساب اس طرح پیر ہو سکتا ہے
کہ جتنا جتنا روپیہ جتنے جتنے ماہ تک تجارت میں لگایا جائے اتنے اتنے روپے اتنے اتنے
مہینوں میں ضرب دے کہ تمام حاصل ضربوں کو جمع کر لیا جائے اور حاصل جمع کو بارہ پر
تقسیم کر کے جو ر قسم نکلے اس کا چالیسواں حصہ زکواۃ میں دیا جائے.مثلاً ڈھائی (۲)
سور و پیه شروع سال میں تجارت پر لگایا جو آخر سال تک بارہ ماہ لگا رہا.دو ماہ کے بعد
بینش روپیہ اور لگا دیا جو آخر سال تک دنیل ماہ تجارت پر لگا رہا.اس کے دو ماہ بعد
پانچ سو روپیہ تجارت پر لگایا جو آخر سال تک آٹھ ماہ تجارت پر لگا رہا.سال ختم
ہونے پر اس طرح حساب کیا جائے.ه : مجموعہ فتاوی احمدیہ جلد اول مثلا - الحکم ، ارنومبر نشائه.
Page 368
۳۶۲
ڈھائی سو روپے بارہ مہینے.بہنیں روپے دس ماہ اور پانچ سو روپیہ آٹھ ماہ تک لگے
ر ہے.اس لئے :-
رفتم
میعاد
حاصل ضرب
3000
200
=
4000
12
x
250
20
8
500
میزان
7,200 =
12,
تمام ضربوں کا حاصل جمع - 7200 روپے آیا.اس کو بارہ پر تقسیم کیا تو 720
600 روپے آئے.لہذا 600 روپے کا چالیسواں حصہ / 15 روپے زکواۃ نکلی.زمینوں کی پیداوار کا نصاب اور شرح
زكواة
علماء اسلام نے زرعی زمین کو دو قسموں میں تقسیم کیا ہے.جس را می یعنی ان علاقوں کی زمین جن
جندرا جی
پر مسلمانوں نے بزور شمشیر قبضہ کیا لیکن وہاں زمین فوجیوں میں تقسیم کرنے کی بجائے حکومت کی ملکیت
میں رہنے دی اور زراعت کے لئے انہیں لوگوں کو دے دی گئی جو اس پر پہلے سے قابض چلے
ا
رہے تھے.ایسی زمین کی پیدا دار پر زکواۃ کی بجائے خراج یعنی مالیہ عائد ہو گا جس کی
شرح حالات اور حکومت کی ضرورت کے لحاظ سے تبدیل ہوتی رہتی ہے.زمین کی دوسری قسم عشری کہلاتی ہے جیسے ارض حجاز کی زمین یا جن علاقوں کی زمین
مسلمان فوجیوں میں تقسیم کر دی گئی ہو اور انہیں ان کا مالک بنا دیا گیا ہو.ایسی زمینوں کی پیداوار
پر عشر یعنی دسواں حصہ بطور نہ کوۃ واجب ہو گا بشر طیکہ بارانی ہوں اور پیداوار پانچ وسق (اندازاً
له : دسق ناپنے کا پیمانہ ایک دستی ۶۰ صاع ۰ ۱۲۵ لیٹر.اس حجم کے پیمانہ میں گیہوں کی جو مقدار
آتی ہے اس کے لحاظ سے با عتبار وزن ایک وسق : ٣ من و اسیر وہ تولہ ہ ماشہ ہرتی.صاع کی مقدار
کی دوسری تحقیق کے مطابق ایک وسق ٣ من ، سیرہ تو لہ ہے.اسلام کا نظام محاصل حث)
Page 369
۳۶۳
اکمیں من ہو.اگر پیداوار اس سے کہ ہو تو اس پر زکواۃ عائد نہ ہوگی ہاں پیدا وار اگر اکیس مین یا
اس سے زیادہ ہو تو اس کا دسواں حصہ ادا کرنا ہوگا.اگر زمین چاہی یا نہری ہے یا چشمہ کے پانی
سے سیراب ہوتی ہے تو زکوۃ کی شرح نصف عشر یعنی بینش واں حصہ ہوگی.یہ زکواۃ تب واجب
ہوگی جبکہ اس زمین سے حکومت مالیہ وصول نہ کرتی ہو اگر مالیہ لگا ہوا ہے تو پھر اصولاً زکواۃ
واجب نہ ہوگی کیونکہ ایک چیز سے دومستقل ٹیکس وصول نہیں کئے جا سکتے
جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ اصولاً زمین کی اُسی پیداوار پر زکوۃ ہے جو قابل ذخیرہ
ہے جیسے اناج خشک پھل مثلاً کھجور کشمش وغیرہ گویا جو پیداوار قابل ذخیرہ نہیں شکلاً
سبزیات یا خربوزہ یا تازہ پھل وغیرہ تو اس پر زکواۃ ادا کرنا ضروری نہ ہو گا.اگر نہ مین بٹائی پر
دی گئی ہو تو مشترکہ پیداوار سے زکوۃ ادا ہو گی اس کے بعد مالک اور مزارع میں بقیہ
پیدا وار تقسیم کی جائے گی.جنگلی شہد جس کی مکھیوں کو پالنے پر انسان کا کچھ خرچ نہیں آتا اگر دنس مشکیزہ کے برابر
حاصل ہو جائے تو ایک مشکیزہ بطور زکواۃ واجب ہوگی گویا شہد کا نصاب دنس مشکیزے تسلیم
کیا جاتا ہے.پالتو مکھیوں کے شہر پر زکواۃ نہیں ہے..جانوروں کا نصاب زکوۃ اور شرح زکوۃ
زکواۃ کے جانوروں سے مراد مویشی ہیں جیسے اونٹ، گائے، بیل، بکری، بھیڑ، چھترا
دنبه وغيره.گھوڑے.خچر اور گدھے کے بارہ میں اختلاف ہے بعض نے انہیں اموال زکواۃ میں شامل
کیا ہے اور بعض نے نہیں کیا.نیز مویشیوں پر زکوۃ تب واجب ہو گی جبکہ وہ قدرتی چرا گاہوں
میں چھرا در پل رہے ہوں اور گھر میں ان کو چارہ ڈالنے کی ضرورت نہ پڑے.نصاب
اونٹوں کا نصاب زکوۃ پانچ ہے.اگر کسی کے پاس پانچ سے کم اونٹ ہوں تو اس پر
نہ کواۃ واجب نہ ہوگی.شرح زکواۃ کی تفصیل یہ ہے :-
Page 370
۳۶۴
۵ راس اُونٹ سے 4 راس تک کے لئے زکواۃ الکبری یا اس کی قیمت
"
"
"
"
بکریاں یا ان کی
V
لم
ا دشمنی یک الا یا انکی
"
"
"
"
"
سوکھی
"
"
N
v
"
اه دوساله را
"
1
H
را سلام کا
را
را
یا ہم نے
"
"
اونٹنیاں ۲ سالہ یا انکی
"
"
"
ا
را
را
"
"
را
"
"
N
کے کچھ
را
۱۰ را کر گیا
را لما را
14 //
ا ۲۴
W
9 + "
کوئی
"
4
الا
۳۵ را
کوئی
/ 69
"
/ 41
اس کے بعد ہر چالیس اونٹوں پر ایک دو سالہ اونٹنی اور پچاس اونٹوں پر ایک سرسالہ
اُونٹنی بطور زکواۃ دینی ہوگی.گائیوں اور بھینسوں کی زکواة :-
گائے اور بھینس ایک ہی جنس شمار ہوتی ہیں اور ان میں بیل اور بھینسے بھی شامل ہیں.پس ان کے نصاب اور زکواۃ کا انحصار ان کی مجموعی تعداد پر ہے.نہ کہ ہر ایک جانور کی الگ
الگ تعداد پر خواہ ان میں سے کسی ایک جنس کی تعداد نصاب سے کم ہو.اگر ان جانوروں
د گائے بھینس کی مجموعی تعداد نصاب کے برابر ہو تو ان پر نہ کواۃ واجب ہوگی.آئندہ جہاں
گائے کا لفظ آئے گا اس میں گائے، بیل، بھینس، بھینسا سب شامل ہوں گے.گائیوں کا نصاب ۳۰ راس ہے.۳۰ سے کم جانوروں پر زکواۃ نہیں.اور ان کی نہ کوۃ
کی شرح ہر ۳۰ راس پر ایک ایک سالہ گائے اور ہر ہم رائس پر ایک دو سالہ گائے ہے مثلاً
۲ راس گائے سے ۳۹ رائس تک کے لئے زکواۃ اگائے اسالہ یا اس کی قیمت
م
"
"
//
09 "
"
" 49"
"
"
"
را
"
11
"
"
"
" 99"
"
دوساله
"
"
۱۱ ۱۲ ساله او مرد ایک یک امر یا نیکی قیمیت
دو گائیں دو سالہ یا ان کی قیمت
تین گائیں ایک سالہ ،
"
Page 371
۴۶۵
راس گائے سے 9 ا ر اس تک کے لئے نہ کواہ اگائے دو سالہ اور دو یک تار اس کی قیمت
"
"
سلام را
ایک یک ساله
السلام را
یا چار یک ساله ،
"
"
"
v
114 /
"
V
"
"
۱۴۹
"
اور اسی طرح آگے حساب چلتا جائے گا.بكریوں وغیرہ کی زکواة :-
بکریاں.بھیڑیں.چھتر سے اور دنیاں ایک ہی جنس شمار ہوتی ہیں اور ان کے نصاب اور
ان کی زکواۃ کا انحصار بھی ان کی مجموعی تعداد پر ہوگا نہ کہ ہر جانور کی الگ الگ تعداد بیت.آئندہ جہاں
بکری کا لفظ آئے اس میں بکرا بکری مینڈھا.بھیڑ.دُنبہ ، دنبی سب شامل ہوں گے
بکریوں کا نصاب ۴۰ راس ہے.چالیس سے کم جانوروں پر زکواۃ نہیں ہے اور ان کی زکواۃ
کی شرح حسب ذیل ہے :-
۴۰ رائس بکری سے ۱۲۰ راس تک کے لئے زکواۃ ، بکری یا اس کی قیمت
"
"
بکریاں ،
کریم
لوگو
مجھے
"
"
۲۰۰
ہوئے
کوئی
تورکی
را
"
"
اس سے اوپر ہر سو بکری پر ایک بکری بطور زکوۃ واجب ہے اور اگر بکریاں پورے سینکڑوں
کی تعداد میں نہ ہوں بلکہ کم ہوں تو کسر یہ کچھ نہ گواہ نہیں ہوگی.پس ۳۰۱ سے لے کہ ۳۹۹ بکریوں
پر بھی تین بکریاں ہی زکواۃ واجب ہوگی.کس کا یہ اصول ہر جانور اونٹ ،گائے وغیرہ کے نصاب
پر عائد ہو گا.
Page 372
۳۶۶
متفرق مسائل
مختلف نصاب والے اموال
اگر کسی کے پاس مختلف قسم کا الگ الگ نصاب زکواۃ والا مال ہو لیکن ان میں سے کوئی بھی
بجائے خود نصاب کے مطابق نہ ہو بلکہ کم ہو خواہ ان سب کی مجموعی قیمت ہزاروں تک پہنچتی ہو تو
زکوۃ واجب نہ ہوگی.مثلاً کسی کے پاس چار اونٹ ۲۹ گائیں ۳۹ بکریاں ۵۱ تولہ چاندی ہے
تو کسی پر زکوۃ واجب نہ ہوگی اور نہ مجموعی قیمت کی بناء پر زکواۃ وصول کی جائے گی کیونکہ ان میں
سے ہر مال کا نصاب زکواۃ الگ ہے اور وہ اسی مال کے ساتھ مختص ہے.سال سے کیا مراد ہے
زکواۃ سے وجوب کے لئے سال سے قمری سال مراد ہے لیکن شروع سال سے ماہ محرم
مراد نہیں بلکہ جس مہینے نصاب کے برابر کوئی مال کسی کی ملکیت.قبضہ اور تصرف میں آئے
گا اس مال کے لئے سال اس مہینہ سے شروع ہوگا اور بارہ قمری مہینے گزرنے پر اس
مال میں زکواۃ واجب ہو گی.اگر سال گزرنے سے پہلے پہلے مال کی نوعیت بدل گئی تو سال بھی
بدل جائے گا.یعنی سال اس ماہ سے شروع ہو گا جس میں یہ نیا مال قبضہ و تصرف میں آیا
ہے مثلاً ایک شخص کے پاس ربیع الاول میں دس ہزار روپیہ آیا چھ ماہ گزر سے کہ شعبان میں
اس نے دس ہزار روپیہ کے مویشی خرید لئے تو اب اس مال پر زکوۃ کی اغراض کے لئے سال ماہ
شعبان سے شروع ہو گا.اگر یہ مویشی سال بھر یعنی اگلے " رجب تک اُس کے پاس ہے تو
ان پر زکواۃ واجب ہوگی اور اگر سال گزرنے سے پہلے پہلے اُس نے مویشی پیج دیئے اور اس
روپیہ سے تجارت کی نیت سے کراکری خرید لی تو پھر سالی اس ماہ سے شروع ہو گا جس
میں اس نے کراکری خریدی ہے.اس طرح اگر سال کے دوران میں مال کی نوعیت بدلتی جائے اور کسی مال پر سال گزرنے
نہ پائے تو اس سرمایہ پر زکواۃ واجب نہ ہوگی.
Page 373
اموال پر زکوٰۃ کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اکتناز ذخیرہ اندوزی.ہور ڈنگ اور مال جمع
کرنے اور مہنگا کر کے بیچنے کی حرص کا قلع قمع کیا جائے اور مال جلد جلد نکالنے اور فروخت
کرنے کی عادت ڈالی جائے.اگر کسی کے قبضہ میں نصاب کے برابر یا اس سے زیادہ کوئی سال ہو مگر سال کے دوران میں
وہ نصاب سے کم رہ جائے لیکن سال کے آخر میں نصاب کے برابر یا اس سے بڑھ جائے تو زکواۃ کے
وجوب میں دوران سال کی کی اثر اندانہ نہ ہوگی اور سال کے آخر میں جو بھی مال موجود ہے اس
پر زکواۃ عائد
ہوگی.اگر سال کے دوران مال گر جائے.پھر ایا جائے.کوئی چھین سے یا کسی اور طرح مالک کے قبضہ
اور تصرف سے نکل جائے لیکن سال کے آخر میں وہی مال مل جائے تو زکوۃ واجب ہوگی ہاں اگر
کئی سال تک وہ مال مالک کو نہ ملے یا اس نے کسی کو قرض دیا ہوا ہو یا زیور یا مویشی کسی کے پاس
رہن رکھے ہوئے ہوں یا دوکاندار کا روپیہ خریداروں کے ذمہ ہو تو ان سب صورتوں میں صرف
اسی سال کی نہ کواۃ واجب ہوگی جس سال یہ مال دوبارہ اس کے قبضہ اور تصرف میں آیا ہے.ایک صاحب نے سوال کیا کہ تجارت کا جو مال خریداروں کی طرف ہوتا ہے اور اگراہی میں
پڑا ہوتا ہے اس پر زکواۃ کا کیا حکم ہے.اس پر سیدناحضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا : -
جو مال معلق ہے اس پر زکواۃ نہیں.جب تک کہ اپنے قبضہ میں نہ آجائے.لیکن
تاجر کو چاہیے کہ حیلہ بہانہ سے زکواۃ کو نہ ٹال دے.آخر اپنی حیثیت کے مطابق اپنے
اخراجات بھی تو اسی مال میں سے برداشت کرتا ہے.تقویٰ کے ساتھ اپنے مال
موجودہ اور معلق پر نگاہ ڈالے اور مناسب دے کر خدا تعالیٰ کو خوش کرتا رہے بعض
لوگ خدا کے ساتھ بھی حیلے بہانے کرتے ہیں یہ درست نہیں ہے.مقروض کا قرضہ اگر اس کی مملوکہ جائیداد اور آمدن سے بڑھ گیا ہے اور اس کی استطاع سے
باہر ہے تو قرضہ کی ادائیگی تک اُس پر زکواۃ واجب نہیں ہے.نابالغ یا دیوانہ کا مالک
نابالغ اور دیوانہ کی ملکیت میں جو مال ہے اگر تو اُسے محفوظ تجارت میں لگانے کے مواقع ہیں
اور اس اعتماد پر اس مال کے نگران نے اُسے تجارت میں لگا دیا ہے تو حسب قواعد زکواۃ واجب
ے: مجموعہ فتاوی احمدیہ جلد مثلا :
Page 374
۳۶۸
ہوگی.ورنہ زکواۃ واجب نہ ہوگی کیونکہ ایسی صورت میں اگر زکواۃ عائد ہو تو سارا سرمایہ اس میں
صرف ہو جائے گا.اور نا بالغ کے مفاد کے لئے مال جمع رکھنے کا مقصد فوت ہو جائے گا.زکواۃ کیا ہے
فتاوی
زکواة کیا ہے " يُو خَذَ مِنَ الْأُمَرَاءِ وَيُرَدُّ إِلَى الْفُقَرَاء یعنی وہ مال جو امراء سے
لے کر فقراء کو دیا جائے اس میں اعلیٰ درجہ کی ہمدردی سکھائی گئی ہے.اس طرح سے باہم
گرم سرد ملنے سے مسلمان سنبھل جاتے ہیں.امراء پر یہ فرض ہے کہ وہ ادا کریں.اگر نہ بھی فرض
ہوتی تو بھی انسانی ہمدردی کا تقاضا تھا کہ غرباء کی مدد کی جائے.مگر اب میں دیکھتا ہوں کہ ہمسایہ
اگر فاقہ مرتا ہو تو پرواہ نہیں اپنے عیش و آرام سے کام ہے جو بات خدا تعالیٰ نے میرے دل
میں ڈالی ہے لیکن اس کے بیان کرنے سے رک نہیں سکتا.انسان میں ہمدردی اعلی درجہ
کا جوہر ہے.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے "لَن تَنالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ
یعنی تم ہرگز ہرگنہ اس نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک اپنی پیاری چیزوں کو ادند کی راہ میں
خرچ نہ کرو.یہ طریق اللہ کو راضی کرنے کا نہیں کہ مثلاً کسی ہندو کی گائے بیمار ہو جائے اور وہ
کہے کہ اچھا اسے منس کے دیتے ہیں.دیعنی صدقہ میں دیتے ہیں).بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ باسی اور سٹری بھی روٹیاں جو کسی کام نہیں آسکتی
ہیں فقیروں کو دے دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے خیرات کر دی ہے.ایسی باتیں اللہ تعا لئے کو
منظور نہیں ہیں اور نہ ایسی خیرات مقبول ہو سکتی ہے وہ تو صاف طور پر کہتا ہے لن تنالوا
الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، حقیقت میں کوئی نیکی نیکی نہیں ہو سکتی جب تک
اپنے پیار سے مال اللہ تعالی کی راہ میں اُس کے دین کی اشاعت اور اس کی مخلوق کی ہمدردی
کے لئے خرچ نہ کرو یا سے
له - سورة العمران : ۱۳ : ۲:- مننا ہندی لفظ ہے اور اس کے معنے صدقہ دینا ہیں :
کے فتاوی حضرت مسیح موعود ، بدی شاه به
:
Page 375
۳۶۹
سوال : سونے کی صورت میں زکواۃ کس طرح ادا کی جائے یعنی اس کا نصاب کیا ہے ؟
جواب : سونے کے لئے ہمارے نزدیک چاندی معیار ہے یعنی اگر کسی کے پاس اتنا سونا ہو جو ہ ۵۲
تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو تو ایسے شخص کو زکوۃ ادا کرنی چاہئے بشرطیکہ ہونا اسے یورکی
شکل میں نہ ہو جسے بالعموم استعمال کیا جاتا ہے اور کبھی کبھار غاریہ مانگنے والی کو پہننے
کیلئے دے دیا جاتا ہے اور بخل سے کام نہیں لیا جاتا
سوال :.شروع سال میں نصاب کے برابر رقم تھی.پھر سال کے دوران میں اس میں اضافہ
ہوتا رہا.ایسی زیادتی کی زکواۃ کے بارہ میں کیا حکم ہے ؟
جواب : اگر سال کے دوران میں سرمایہ بڑھ جائے مثلاً دن کا پندرہ ہزار ہو جائے تو زکواۃ
۵ ہزار پر عائد ہو گی خواہ پانچ ہزار رو پیدا ایسا ہو جو سال گزرنے سے ایک دو روز ہی
پہلے میستر آیا ہو.غرض زائد آمدن سابقہ سرمایہ کے تابع ہو گی اور اس کے لئے سال
سرمایہ کے تابع ہو گی اور اس کے لئے
گزرنے کی شرط نہیں ہوگی.سوال : کیا سیکورٹی اور پراویڈنٹ فنڈو میعادی امانت رفکسڈ ڈیپازٹ زکواۃ سے
مستثنی ہیں.امانت تابع مرضی ( CURRENT ACCOUNT ) کے بارہ میں کیا حکم ہے ؟
جوا ہے :.قرض میعادی امانت سیکورٹی ضمانت میں دی ہوئی رقم اور پراویڈنٹ فنڈ پر زکواۃ
نہیں.البتہ جس سال یہ رقوم وصول ہوں اس سال کی زکواۃ ادا کرنی چاہیئے.امام مالک اپنی کتاب موطا میں فرماتے ہیں :-
الاَمْرُ الَّذِي لَا اِخْتِلَانَكَ فِيهِ عِنْدَ نَا فِي مَسْئَلَةِ الدَّيْنِ إِنَّ
صَاحِبَهُ لَا يُزَكِّيهِ حَتى يَقْبِضَهُ صَاحِبُهُ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ.اللَّا زَكوةٌ وَاحِدَهُ له
ہمارے (یعنی مدینہ کے علماء کے نزدیک یہ مسئلہ متفق علیہ ہے کہ جو قرض مقروض کے
پاس کئی سال تک رہے اس پر زکواۃ نہیں البتہ جس سال یہ قرض وصول ہو صرف اس
سال
کی زکواۃ ادا کرنا ہوگی.جو بھائی قرض کا ہے وہی میعادی امانت اور سیکورٹی وغیرہ کا
ہے.امام مالک نے اپنے مسلک کی تائید میں حدیث بھی پیش کی ہے.علاوہ ازیں زکوۃ
کی ایک عرض یہ بھی ہے کہ مال مالک کے پاس بند نہ پڑا رہے بلکہ لا محالہ وہ مجبور ہو کر اسے
کاروبار میں لگائے یا کسی دوسرے کو اس سے استفادہ کرنے دے ورنہ زکواۃ اس کے
: اوجز المسالك شرح موطا مالک جلد ۳ ص :
Page 376
٣٠٠
مال
کو کھا جائے گی.ظاہر ہے کہ قرض میعادی امانت وغیرہ کی صورت میں یہ مقصد حاصل
ہو جاتا ہے.اس لئے ایسے سرمایہ پر زکواۃ نہیں ہے.نیزا کیسے حالات میں اگر نہ کواہ ضروری
ہو تو کچھ عرصہ کے بعد سارا قرض اور ساری امانت زکواۃ میں ختم ہو جائے گی حالانکہ شریعیت
کا یہ منشاء نہیں.قرض بززكوة
ایک شخص کا سوال حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوا کہ جو پیر
کسی شخص نے کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے کیا اس کو زکواۃ دینی لازم ہے؟ فرمایا نہیں لے
مکانات وجواہراتے پر زکواۃ
رو
سوال
پیش ہوا کہ پانچ سوروپیہ کا حصہ ایک مکان میں ہے کیا اس حصہ پر رکواہ ہے یا نہیں ؟
حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا.جواہرات و مکانات پر کوئی زکوۃ نہیں.مکارے اور تجار تھے مال پر زکوة
ایک شخص کے سوال کے جواب میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ مکان خواہ
ہزار روپیہ کا ہو اس پر زکواۃ نہیں اگر کرایہ پر چلتا ہو تو آمد پر زکواۃ ہے.ایسا ہی تجارتی
مال پر جو مکان میں رکھا ہے.نہ کواۃ نہیں.حضرت عمریض چھ ماہ کے بعد حساب لیا کرتے
تھے اور روپیہ پر زکواۃ لگائی جاتی تھی " سے
جماعتی چندہ اور زکواۃ
سوال : اگر چندہ عام یا چندہ وصیت دینے والا یہ نیت کر لے کہ اس میں اس قدر زکواۃ بھی
شامل ہے تو پھر کیا زکواۃ کی علیحدہ طور پر ادائیگی کی ضرورت ہے ؟
ه البدر ۲۱ فروری شندا - فتاوی مسیح موعود ها : سه : البدرم ا فروری ماده - فتادی مسیح موعود ها
: البدر ۴ از فروری شکله - فتاوی مسیح موعود ها :
_
Page 377
};
جواہے :- زکواۃ تو کم از کم مالی صدقہ ہے جو ہر صورت میں خواہ ضرورت ہو یا نہ ہو صاحب نصاب
کو ادا کرنا اور خلیفہ وقت کی وساطت اور اجازت سے خرچ کرنا ہوتا ہے.لیکن چندہ
کی بنیاد جماعتی فیصلہ اور ضرورت پر ہے.اگر مسلسل کو ضرورت ہے تو چندہ لگے گا ورنہ
نہیں لگے گا.ان وجوہات کی بناء پر چندہ میں زکواۃ محسوب کرنا درست نہیں.اور مرکزی
بیت المال کی ہدایت بھی یہی ہے.مصارف زكوة
شروع اسلام میں اسلامی حکومت کے محصل جو زکوۃ وصول کرتے وہ مقامی ضروری
اخراجات کے لئے مناسب رقم چھوڑ کر باقی مرکزی بیت المال میں پہنچا دیتے اور مرکزی
بیت المال اللہ تعالیٰ کے رسول اور آپ کے بعد خلیفہ وقت کی ہدایت کے مطابق مقررہ
مصارف میں اسے خرچ کرتا تھا.تاہم اصولاً زکواۃ کی آمدن حسب گنجائش ان تمام اخراجات
کے لئے خرچ ہو سکتی ہے جو حکومت کو محتاج اور ضرورت مند معاشرہ کی ضرورتوں کو
پورا کرنے کے لئے کرنے پڑتے ہیں.اگر ہم حکومت اسلامیہ کی وہ ذمہ داری مائیں جن کے پیش نظر حضرت عمر نے سب کے
گزارے کے سامان بہم پہنچنے کے انتظامات کئے تھے تو اس کے ساتھ یہ بھی مانا پڑے
گا کہ زکواۃ حکومت کی مختلف قسم کی ذمہ داریوں پر خرچ کی جاسکتی ہے.گو اس کے پہلے اور
ترجیحی حقدار غرباء ہیں.بہر حال زکواۃ کہاں خرچ کی جائے اس کے مستحق کون لوگ ہیں اس بارہ میں اللہ تعالیٰ
نے اپنے اس ارشاد میں اصولی رہنمائی فرمائی ہے :
إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤَلَّفَةِ تُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّتَابِ وَالْغَرِمِينَ وَفِي
سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ فَرِيضَنَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللهُ عَلِيْمٌ حَكِيمُ
صدقات تو صرف فقراء اور مساکین کے لئے ہیں اور ان کے لئے جو ان صدقات
کے جمع کرنے کے لئے مقرر کئے گئے ہیں نیز ان کے لئے جن کے دلوں کو اپنے ساتھ
له - التوبة :.
Page 378
جوڑنا مطلوب ہوا اور اسی طرح قیدیوں اور قرضداروں کے لئے اور ان کے لئے جو
اللہ کے راستہ میں جنگ کرتے ہیں اور مسافروں کے لئے یہ فرض اللہ کا مقرر کردہ
ہے اور اللہ بہت جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے "
اس آیت میں زکوٰۃ کے آٹھ مصارف بیان کئے گئے ہیں جن کی تفصیل یہ ہے :-
ا فقراء
فقیر کی جمع ہے اور اس سے مراد وہ حاجتمند ہے جو اپنا گزارا چلا نے کیلئے دوسروں کی مدد
کا محتاج ہے اور روزمرہ کی ضروریات کے لئے بھی اس کے پاس کچھ نہیں.مساکین
مسکین کی جمع ہے اور اس سے مراد وہ ضرورت مند ہے جیسے حالات نے بٹھا دیا ہو
بے دست دیا کہ دیا ہو گویا صورت حال کے ہاتھوں وہ بالکل بے کار ہو کر رہ گیا ہو.مثلاً ایک اچھا بھلا کا ریگر ہے لیکن اپنے فن سے کام لینے کے لئے جن آلات کی ضرورت
ہے وہ اس کے پاس نہیں اور نہ وہ کہیں سے مہیا کر سکتا ہے.مسکین کے ایک معنے یہ بھی ہیں کہ وہ کسی سے اپنی حالت بیان
نہیں کرتا اپنی غربت
کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیتا گویا آیت قرآنی :-
تَعْرِفُهُمْ بِسِيْمُهُمْ لَا يَسْتَلُونَ النَّاسَ الْعَانَا.له
کی تصویر ہے.اس آیت میں حکومت کو بھی یہ توجہ دلائی گئی ہے کہ اُسے یہ طریق اختیار نہیں کرنا
چاہیئے کہ جو واویلا کر سے اس کا مطالبہ مان لیا جائے اور جو ضرورت مند ہونے کے
با وجود خاموش رہے اسے نظر انداز کر دیا جائے.-۳- کارکنان وصولی تقسیم کاره
نہ کواۃ کی وصولی اور اُس کی تقسیم کا انتظام کرنے والے کارکنان کو بھی مت زکواۃ سے
گزارہ دیا جا سکتا ہے.وَالْعَامِلِینَ عَلَيْهَا سے یہی لوگ مراد ہیں.غرض زکواۃ
ه : - البقرة : ۲۷۴ :
Page 379
کے نظم ونسق کے کارکن اور شکمہ مال کے کا رند سے زکواۃ کی آمد میں سے گزارا لے سکتے ہیں.مؤلفة القلوب
حوصلہ افزائی اور سہارا دینے کے لئے کچھ خرچ کرنا خواہ اس کا مقصد کسی کو اسلام سے
مانوس کرنا ہو یا ملک و ملت کے سیاسی مفاد اس کے مقتضی ہوں مثلاً کسی علاقہ میں کچھ
لوگ مسلمان ہوئے ہیں جس کی وجہ سے مخالفوں نے ان کے کاروبار کو برباد کر دیا ہے.یا
اسلام کی طرف میلان رکھتے ہوں لیکن اپنی مشکلات سے ڈرتے ہوں ایسے لوگوں کی تالیف
قلوب کے لئے زکواۃ کی مد سے خرچ کرنا بالکل روا اور بجا ہو گا.ه - المرقاب
رقبة کی جمع ہے.اس تھے مجھے گردن کے ہیں.اس کے معنے یہ ہیں کہ کسی کی گردن حوادث
زمانہ کی وجہ سے دوسرے کے قبضہ میں آگئی ہو.وہ اس کی مرضی کے بغیر ہل جبل نہ سکتا ہو
جیسے دشمن کے ہاتھ میں قید ہو گیا ہو.یا قرض میں اس کا رواں رواں ڈوب چکا ہو اور
قرض خواہوں نے اس کا ناطقہ بند کر رکھا ہوا ایسے شخص کی زکواۃ کی آمدن سے گلو خلاصی
کرائی جاسکتی ہے.غار مین
غارم کی جمع ہے.یعنی وہ جس پر نا گہانی حادثہ کی وجہ سے چھٹی پڑ گئی ہو.غلطی سے وہ کسی کا
بھاری نقصان کر بیٹھا ہوا اور اس کی ذمہ داری اس پر آپڑی ہو یا اس کے کسی عوز نیرہ
نے
کوئی غلطی کی ہو اور اس کی چٹی اُس نے اپنے ذمہ لے لی ہو.ایسے مصیبت زدہ کی مدد
نہ کواۃ کی آمد سے کی جاسکتی ہے.في سبيل الله
اللہ کی راہ سے مراد ایسے تمام کام جو اسلام اور مسلمانوں کی بہبود.ان
کی تنظیم حفاظت
اور استحکام اور دوسری شہری ضروریات کے لئے حکومت اور جماعت کو کرنے پڑتے ہیں یہ
Page 380
۳۷۴
سب ضرورتیں زکواۃ کی مد سے بھی پوری کی جاسکتی ہے.ابن السبيل
ابن السبیل سے مراد مسافر ہے.مسافروں کی فوری اور مستقل ضروریات زکوۃ کی مد سے
پوری کی جاسکتی ہیں.مثلاً سرائیں اور رہائش گاہیں بنانا.راستہ کی حفاظت کیلئے چوکیاں
قائم کرنا.سڑکیں اور پل بنانا.دختر معلومات کھولنا یا کھانا مفت مہیا کرنا.غرض سیرو
سیاحت اور تجارتی سفروں کے فروغ کے لئے ضروری اخراجات مذکورہ مد سے ادا
کئے جا سکتے ہیں.عام ہدایت کے لئے اللہ تعالیٰ نے زکواۃ کے یہ آٹھ مصرف بیان فرمائے ہیں.یہ اصولی
رہنمائی ہے.ورنہ امام وقت کو یہ اختیار ہے کہ اگر حالات کا تقاضہ ہو کہ ساری کی ساری زکواۃ
ان میں سے کسی ایک مصرف پر خرچ کی جائے تو ایسا کرنا جائزہ اور منشاء شریعیت کے عین
مطابق ہے.سید کے لئے زکواۃ
1 - سوال ہوا کہ غریب سید ہو تو کیا وہ زکواۃ لینے کا مستحق ہوتا ہے یا نہیں؟
حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا.اصل میں منع ہے اگر اضطراری حالت ہو
فاقہ پر فاقہ ہو تو ایسی مجبوری کی حالت میں جائتہ ہے.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا ما
اضطرِرْتُمْ إِلَيْهِ " والانعام : ١٣٠)
حدیث سے فتوی تو یہ ہے کہ نہ دینی چاہیئے.اگر سید کو اور قسم کا رزق آتا ہو تو
اُسے زکواۃ لینے کی ضرورت ہی کیا ہے.ہاں اگر اضطراری حالت ہو تو اور بات
ہے."
ر حال اصل یہ ہے کہ زکواۃ مرکز کی وساطت سے خرچ ہونی چاہیئے.آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رض اور حضرت عمریضہ کے عہد مبارک ہیں یہی طریق جاری تھا
ه الحکم ۲۳ اگست تنشه.فتاوی مسیح موعود ص ۱۳۲
Page 381
۳۷۵
ہاں اگر کسی مقامی مستحق کی مدد کرنا مقصود ہو یا کوئی جماعت یا فرد زکواۃ کی ساری
رقم کو مقامی طور پر خرچ کہ نا چاہتا ہو تو پھر پہلے سے اس کی اجازت مرکز سے منگوا
لینی چاہیئے.غریب سید کو زکواۃ دینے کی اجازت کا دارو مدار خلیفہ وقت کی مرضی
پر ہے.سوال مدد کا ہے جو ضروری ہے کس مد سے ہو یہ بالکل الگ امر ہے
دراصل آغاز اسلام میں بیت المال کی آمدن کی مختلف مدات تھیں.آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ داروں کی مدد متد زکواۃ کی بجائے دوسری مدات سے
کی جاتی تھی اور نہ کواۃ کی مدائن پر خرچ نہیں ہوتی تھی لیکن جب یہ انتظام باقی
نہ رہا تو پھر یہ تمیز اٹھ گئی.چنانچہ فقہ کے مشہور بزرگ حضرت امام ابو حنیفہ نے یہی
فتوی دیا ہے کہ
؟
۲ - قرآن کی تعلیم دینے والے استاد کو بطور تنخواہ ہ کواۃ کی مد سے رقم دی جاسکتی ہے.اسی
طرح غریب طالب علموں کو زکواۃ کی مد سے وظائف دیئے جا سکتے ہیں.خلاصہ کلام یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء راشدین نے کے بعد حالات چونکہ
بدل گئے ہیں اس لئے بعض آئمہ نے حالات کی تبدیلی سے مجبور ہو کر اضطرار کے پیش نظر جوانہ
کا فتویٰ دیا ہے.حضرت مسیح موعود علیہ السلام حضرت خلیفہ اسیح الثانی رضی اللہ عنہ نے بھی اضطرار کا پہلو
اختیار فرمایا ہے.مطلقا جوانہ کا نہیں.یہی وجہ ہے کہ حضرت خلیفتہ المسیح الثانی نے تفسیر کبیر
میں مسلمانوں کی اس غفلت پر ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا ہے اور اسے قومی انحطاط کا ایک
اہم سبب قرار دیا ہے یہ
ہے :- شرح معانی الآثار طحاوی ہے.شامی کا نیل الاوطار کتاب الزکواة :
:- تفسير كبير سورة البقرة ما :