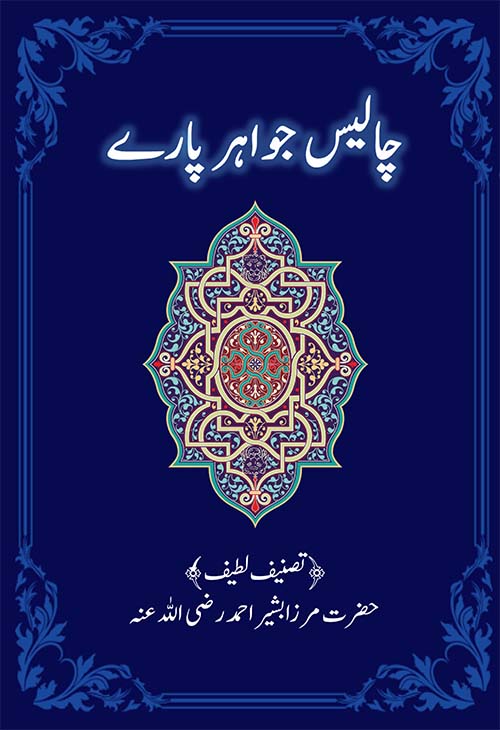Complete Text of Chalees Jawahir Parey
Content sourced fromAlislam.org
Page 1
چالیس جواہر پارے
تصنیف لطیف
حضرت مرزا بشیر احمد رضی اللہ
Page 2
ISLAM
INTERNATIONAL
PUBLICATIONS LTD
چالیس جواہر پارے
تصنیف: حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ عنہ
Chaalees Jawaahar Paarei (Urdu)
A collection of Ahaadees by Hazrat Mirza Bashir Ahmad,
May Allah be pleased with him
First published in Pakistan, 1950
Second edition published in India, 1976
Third and Fourth edition published in India, 1999
Fifth edition published in India, 2001
Sixth edition published in India, 2012 (ISBN: 978-91-7912-006-6)
Present edition published in the UK, 2021
O Islam International Publications Ltd.Published by:
Islam International Publications Ltd
Unit 3, Bourne Mill Business Park,
Guildford Road, Farnham, Surrey UK, GU9 9PS
Printed in the UK at:
Raqeem Press, Farnham, Surrey
For further information, please visit www.alislam.org
Cover design: Dawood Ismail
ISBN: 978-1-84880-404-3
10987654321
Page 3
بِسْمِ الله الرحمن الر
پیش لفظ
اللہ تعالیٰ نے جوامع الکلم حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بارہ میں شہادت دی
کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحى (النجم (۴-۵) یعنی یہ پاک نبی اپنی
خواہش نفس سے کلام نہیں کرتا بلکہ یہ تو ایک وحی ہے جو اتاری جارہی ہے.اللہ تعالیٰ کے محبوب
حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کلمات احادیث کی مختلف کتب میں محفوظ ہیں.کتاب چالیس جواہر پارے حضرت قمر الانبیاء مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ عنہ کی مرتب کردہ
ہے جس میں آپ نے علم حدیث کا بنیادی تعارف بیان فرمانے کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ رسول
کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چالیس احادیث مع ترجمہ و تشریح درج فرمائی ہیں.مکرم محمد فراز مجو کہ صاحب اور مکرم عبد القدیر قمر صاحب نے حوالہ جات مکمل کرنے
نیز مکرم صباحت احمد چیمہ صاحب نے کتاب کو فائنل کرنے کے کام میں مدد کی ہے.اللہ تعالیٰ ان
کو اس کا اجر عطا فرمائے.آمین
یہ تمام احادیث مختصر لیکن نہایت جامع معانی رکھنے والی ہیں.احباب کو چاہیے کہ ان کو
یاد کرنے کی بھی کوشش کریں اور اپنے بچوں کو بھی یہ کتاب پڑھائیں.اس کتاب کو انگلستان سے
طبع کر وایا جارہا ہے.اللہ تعالیٰ اس کی طباعت ہر لحاظ سے مبارک اور مفید ثابت فرمائے.آمین
منیر الدین شمس
ایڈیشنل وکیل التصنيف
جون ۲۰۲۱ء
Page 5
V
بِسْمِ اللهِ الرَّحمٰنِ الرَّحِيم
نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمُ
عرض حال
میں نہیں جانتا کہ اس کی وجہ کیا ہے لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ مجھے بچپن سے
حدیث کے علم کے ساتھ ایک قسم کا فطری لگاؤ رہا ہے اور جب کبھی بھی میں کوئی حدیث
پڑھتا ہوں تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ میں گو یار سول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس
میں شریک ہو کر حضور کے مقدس کلام سے مشرف ہو رہا ہوں.میرا تخیل مجھے آج سے
چودہ سو سال قبل مکہ مکرمہ کی مسجد حرام اور مدینہ طیبہ کی مسجد نبوی اور حرمین شریفین کی
گلیوں اور عرب کے صحرائی رستوں میں پہنچا کر رسول اکرم صلی للی کم کی روحانی صحبت اور
معنوی رفاقت کا لطف عطا کر دیتا ہے اور پھر میں کچھ وقت کے لئے دنیا سے کھویا جا کر اس فضا
میں سانس لینے لگتا ہوں جس میں ہمارے محبوب آقا نے اپنی خداداد نبوت کے تئیں
مبارک سال گزارے.لیکن غالباً جس حدیث نے میرے دل اور دماغ پر سب سے زیادہ گہرا اور سب سے
زیادہ وسیع اثر پیدا کیا وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایسے ارشاد سے تعلق رکھتی
ہے جس میں فقہ اور علم کلام کا تو کوئی عصر شامل نہیں مگر میرے ذوق میں وہ اسلام اور
روحانیت کی جان ہے.روایت آتی ہے کہ
Page 6
vi
”ایک دفعہ ایک غریب مسلمان آنحضرت صلی ال نیم کی خدمت میں حاضر ہوا اس
کے ماتھے پر عبادت اور ریاضت کا تو کوئی خاص نشان نہیں تھا مگر اس کے دل میں محبت
رسول کی ایک چنگاری تھی جس نے اس کے سینہ میں ایک مقدس چراغ روشن کر رکھا تھا.اس نے قرب رسالت کی دائگی تڑپ کے ماتحت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈرتے
ڈرتے پوچھا.” یارسول اللہ ! قیامت کب آئے گی؟“
آپ نے فرمایا : تم قیامت کا پوچھتے ہو کیا اس کے لئے تم نے کوئی تیاری بھی کی
ہے ؟ اس نے دھڑکتے ہوئے دل اور کپکپاتے ہوئے ہونٹوں سے عرض کیا.”میرے آقا !
نماز روزے کی تو کوئی خاص تیاری نہیں لیکن میرے دل میں خدا اور اس کے رسول کی سچی
محبت ہے.“ آپ نے اسے شفقت کی نظر سے دیکھا اور فرمایا: الْمَرُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ یعنی
پھر تسلی رکھو کہ خدائے و دود کسی محبت کرنے والے شخص کو اس کے محبوب سے جدا نہیں
کرے گا.“
یہ حدیث میں نے بچپن کے زمانہ میں پڑھی تھی لیکن آج تک جو میں بڑھاپے کی
عمر کو پہنچ گیا ہوں میرے آقا کے یہ مبارک الفاظ قطب ستارے کی طرح میری آنکھوں
کے سامنے رہے ہیں اور میں نے ہمیشہ یوں محسوس کیا کہ گویا میں نے ہی رسول خدا سے یہ
سوال کیا تھا اور آپ نے مجھے ہی یہ جواب عطا فرمایا اور اس کے بعد میں اس نکتہ کو کبھی نہیں
بھولا کہ نماز اور روزہ اور حج اور زکوۃ سب بر حق ہے مگر دل کی روشنی اور روحانیت کی چمک
خدا اور اس کے رسول کی سچی محبت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی.اگر انسان کو یہ نعمت
Page 7
vii
حاصل ہو جائے تو ظاہری عمل زندگی کی روح سے معمور ہو کر اس کے پیچھے پیچھے بھاگا آتا ہے
لیکن اگر انسان کو یہ نعمت حاصل نہ ہو تو پھر خشک عمل ایک مردہ لاش سے زیادہ حقیقت
نہیں رکھتا جو ظاہر پرست لوگ اپنے سینوں سے لگائے پھرتے ہیں.خدا جانتا ہے کہ اسی محبت رسول کے جذبہ کے ماتحت میں نے یہ رسالہ لکھا ہے تا
اگر خدا کو منظور ہو تو اس کے پڑھنے والوں کے دلوں میں اس محبت کی چنگاری پیدا ہو جو
ہر نیک عمل کی روح اور ہر اعلیٰ خلق کی جان ہے اور وہ اپنے محبوب آقا کے ارشادات کو دلی
شوق و ذوق سے سنیں اور اپنے لئے حرز جان بنائیں اور خود میرے واسطے بھی وہ بخشش اور
مغفرت اور شفاعت رسول کا موجب ہو.آمین یا ارحم الراحمین!
خاکسار
مرزا بشیر احمد
آف قادیان
Page 9
ix
عنوان باب
حدیث کی تعریف
فہرست مضامین
حدیث بیان کرنے کا طریق
راویوں کے طبقات
حدیث کی مشہور کتابیں
حدیث کی اقسام
حدیث اور سنت میں فرق
چالیس حدیثوں کا مجموعہ
چھ شرائط ایمان
صفحہ نمبر
1
2
2
3
6
9
11
13
16
22
46
26
31
پانچ ارکان اسلام
آنحضرت علی کم کی پانچ امتیازی خصوصیات
آنحضرت ملا نام آخری شریعت لانے والے نبی ہیں
اعمال کا اجر نیت کے مطابق ملتا ہے
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Page 10
X
13
14
خدا کی نظر دلوں پر ہے
مجاہد اور قاعد مسلمان میں درجہ کا فرق
15 ہر نا پسندیدہ بات دیکھ کر اصلاح کی کوشش کرو
16
17
18
19
20
جو بات اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی کیلئے پسند کرو
بھائی خواہ ظالم ہو یا مظلوم اس کی مدد کرو
اسلام میں اطاعت کا بلند معیار
ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا افضل ترین جہاد ہے
چھوٹوں پر رحم کرو اور بڑوں کے حق پہچانو
34
37
42
47
50
54
57
61
21 شرک، والدین کی نافرمانی اور جھوٹ سب سے بڑے گناہ ہیں 64
22
اولا د کا بھی اکرام کرو اور انہیں بہترین تربیت دو
23 بیوی کے انتخاب میں دینی پہلو کو مقدم کرو
24 بہتر انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہتر سلوک کرے
26
دیندار وہ عورت ہے جو اپنے خاوند کا حق ادا کرتی ہے
یتیموں کی پرورش کرنے والا جنت میں رسول پاک صلی علیکم
70
73
78
82
85
کے ساتھ ہو گا
Page 11
xi
27 ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک کی انتہائی تاکید
28 جنگ کی تمنا نہ کرو لیکن اگر لڑائی ہو جائے تو ڈٹ کر مقابلہ کرو
88
91
29
دشمن سے بد عہدی نہ کرو اور بچوں اور عورتوں کے قتل سے بچو 94
30 سات تباہ کرنے والی چیزیں ( قتل ناحق، سود خوری، بہتان تراشی
وغیره)
31 نشہ پیدا کرنے والی چیزوں کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے
33
دھوکہ باز انسان سچا مسلمان نہیں سمجھا جا سکتا
دوسری قوموں کی مشابہت اختیار نہ کرو
34 دل ٹھیک ہو تو سارے اعضاء خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں
35
جو بات دل میں کھٹکے اس سے اجتناب کرو
36 احساس کمتری ایک سخت مہلک احساس ہے
37 سچی تو بہ گناہ کو مٹادیتی ہے
38
40
مومن ایک سوراخ سے دو دفعہ نہیں کاٹا جاتا
اچھے اخلاق سے بہتر کوئی عمل نہیں
دوسری قوموں کے معزز لوگوں کا احترام کرو
97
106
110
112
115
118
121
124
127
130
134
Page 12
137
140
143
147
151
154
158
162
165
xii
41 مزدور کو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری دو
42 بدترین دعوت وہ ہے جس میں صرف امیروں کو بلایا جائے
43 اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے
44
45
46
47
اپنے وارثوں کو اپنے پیچھے اچھی حالت میں چھوڑو
ہر شخص اپنی جگہ حاکم ہے اور اپنی حکومت کے دائرہ میں
جواب دہ ہو گا
علم سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے
ہر حکمت کی بات مومن کی اپنی ہی کھوئی ہوئی چیز ہوتی ہے
48
خاتمہ اور دعا
49 کتابیات
Page 13
1
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيم
تمهید
حدیث کی تعریف
حدیث ایک عربی لفظ ہے جس کے بنیادی معنی ایسی نئی بات کے ہیں جو یا تو بالکل ہی
نئی ہو یا نئے انداز میں پیش کی گئی ہو.چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام بھی نئے اور
بیش بہا حقائق پر مشتمل ہے اس لئے اس کا نام اصطلاحاً حدیث رکھا گیا ہے.پس حدیث اس
مقدس کلام کا نام ہے جو ہمارے آقا آنحضرت صلی اللہ ظلم فداہ نفسی) کی زبان مبارک سے نکلا یا
جس میں آپ کی پاکیزہ زندگی کا کوئی چشم دید واقعہ بیان کیا گیا اور پھر آپ کے صحابہ اور بعد
کے مسلمان راویوں کے ذریعہ وہ کچھ عرصہ کے بعد تحریر میں لا کر محفوظ کر لیا گیا.عربوں کا
حافظہ جیسا کہ عیسائی مؤرخوں تک نے بر ملا تسلیم کیا ہے غیر معمولی طور پر عمدہ تھا اور جو بات
بھی وہ سنتے یا دیکھتے تھے اسے بڑی حفاظت کے ساتھ یاد رکھتے تھے اور چونکہ حدیث ایک
مقدس دینی علم ہے اس لئے اس معاملہ میں خصوصیت کے ساتھ بڑی احتیاط اور بڑی امانت
اور دیانت سے کام لیا گیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو غیر معمولی حفاظت
کے ساتھ پیچھے آنے والی نسلوں تک پہنچایا گیا.بے شک بعض راوی حافظہ اور سمجھ اور
دیانت کے لحاظ سے ایسے پکے نہیں تھے کہ ان کی روایتوں پر پورا اعتماد کیا جاسکے مگر حدیث
Page 14
2
جمع کرنے والے بزرگوں نے ایسے پختہ اصول مقرر کر دیئے ہیں کہ ان کے ذریعہ مناسب
چھان بین کے ساتھ صحیح حدیثوں کو کمزور حدیثوں سے الگ کیا جا سکتا ہے.حدیث بیان کرنے کا طریق
حدیث بیان کرنے کا طریق عموماً یہ ہوتا تھا کہ جس صحابی نے آنحضرت صلی الم کی
زبانِ مبارک سے کوئی بات سنی ہوتی تھی یا آپ کو کوئی کام کرتے دیکھا ہو تا تھا تو وہ اسے
اشاعت علم کی غرض سے ایسے لوگوں تک پہنچاتا تھا جنہوں نے یہ بات نہیں سنی یا نہیں
دیکھی ہوتی تھی یا جنہوں نے آنحضرت صلی اللہ علم کا مبارک زمانہ نہیں پایا ہو تا تھا اور حدیث
بیان کرنے کے الفاظ عموماً اس قسم کے ہوتے تھے کہ میں نے فلاں شخص سے یہ بات سنی
ہے کہ اس نے آنحضرت صلی ایم کے فلاں صحابی سے سنا کہ اس نے فلاں موقع پر آنحضرت
صلى ال علم کو یوں ارشاد فرماتے ہوئے سنایا یہ کام کرتے ہوئے دیکھا...اور پھر یہ لوگ اسی طریق
پر ایمان تازہ کرنے کی غرض سے یا اشاعت علم کی غرض سے دوسرے لوگوں تک روایت
پہنچاتے چلے جاتے تھے اور اس طرح راویوں کے ایک مسلسل اور با قاعدہ سلسلہ کے ذریعہ
آنحضرت صلی الی یم کی احادیث بعد میں آنے والے لوگوں کے لئے محفوظ ہو گئیں.الله
راویوں کے طبقات
حدیث کے راوی کئی طبقات میں منقسم ہیں.سب سے اوپر کا مسلمان راوی جس نے
کوئی بات براہ راست آنحضرت صلی اللہ ظلم کے منہ سے سنی ہو یا آپ کو کوئی کام کرتے ہوئے خود
Page 15
3
اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو صحابی کہلاتا ہے.اس سے نیچے کا راوی جو صحابی سے سن کر آگے
روایت کرتا ہے.محدثین کی اصطلاح میں تابعی کہلا تا ہے اور اس سے نیچے کا راوی تبع تابعی
کہلا تا ہے اور اس کے بعد عام راویوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے.اسی طرح حافظہ اور سمجھ اور
دیانت کے لحاظ سے بھی راویوں کے مختلف طبقات سمجھے جاتے ہیں.حدیث کی مشہور کتابیں
حدیث کی روایتیں عموماً دوسری صدی ہجری کے وسط سے لے کر تیسری صدی
ہجری کے آخر تک جمع ہو کر کتابی صورتوں میں مرتب کرلی گئی تھیں.حدیث کی کتابیں یوں تو
بہت ہیں مگر ان میں سے چھ کتابیں خاص طور پر زیادہ صحیح اور زیادہ مستند سمجھی جاتی ہیں.اس
لئے ان چھ کتابوں کا نام صحاح ستہ (یعنی حدیث کی چھ صحیح کتابیں ) مشہور ہو گیا ہے.ان چھ
کتابوں کے نام یہ ہیں.(1) صحیح بخاری: مرتبه امام محمد بن اسماعیل البخاری (ولادت ۱۹۴ھ وفات ۲۵۶ھ)
امام بخاری کی یہ کتاب حدیث کی تمام کتابوں میں سب سے زیادہ صحیح اور سب سے زیادہ مستند
سمجھی جاتی ہے اور امام بخاری کا ذاتی مقام بھی مسلمہ طور پر سب محد ثین میں بالا سمجھا گیا ہے اسی
لئے صحیح بخاری کا نام اصح الکتب بعد کتاب اللہ (یعنی کتاب اللہ کے بعد سب سے زیادہ صحیح
کتاب) مشہور ہو گیا ہے.
Page 16
4
(۲) صحیح مسلم: مرتبہ امام مسلم بن الحجاج النیشا پوری ( ولادت ۲۰۴ھ وفات ۲۶۱ھ)
ان کی کتاب صحاح ستہ میں دوسرے نمبر پر شمار ہوتی ہے اور نہایت عمدہ اور قابل اعتماد مجموعہ
سمجھی گئی ہے.اکثر محدثین صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو ملا کر صحیحین (یعنی حدیث کی دو صحیح ترین
کتابیں) کا نام دیتے ہیں.(۳) جامع ترمذی: مرتبہ امام ابو عیسی محمد بن عیسیٰ الترمذی (ولادت ۲۰۹ھ وفات ۲۷۹ھ)
یہ امام بخاری کے شاگرد تھے.ان کا مجموعہ احادیث بھی نہایت اعلیٰ مقام پر مانا گیا ہے.(۴) سنن ابی داؤد: مرتبه امام ابوداؤد سلیمان بن الاشعث السجستانی ( ولادت ۲۰۲ھ وفات
۲۷۵ھ)
فقہی مسائل کی تدوین میں انہیں بہت ارفع مقام حاصل ہے مگر اس بارے میں محققین
میں اختلاف ہے کہ جامع ترمذی اور سنن ابی داؤد میں کس کا مقام زیادہ بلند ہے.(۵) سنن النسائی: مرتبہ امام احمد بن شعیب النسائی ( ولادت ۲۱۵ھ وفات ۳۰۶ھ)
امام نسائی بھی حدیث کے بڑے ائمہ میں سے ہیں اور ان کی کتاب کا درجہ صحاح ستہ میں عموماً
پانچویں نمبر پر مانا گیا ہے.(1) سنن ابن ماجه : مرتبه امام محمد بن یزید ابن ماجه القزوینی ( ولادت ۲۰۹ھ وفات ۲۷۳ھ)
Page 17
یہ کتاب صحاح ستہ میں چھٹے یعنی آخری نمبر پر سمجھی جاتی ہے.سنن ابن ماجہ بھی حقیقتاً
ایک عمدہ کتاب ہے.ان جمله محدثین نے صحیح حدیثوں کی تلاش اور چھان بین میں اپنی عمریں خرچ کر کے
لاکھوں حدیثوں کے ذخیرہ میں سے اپنے مجموعوں کا انتخاب تیار کیا ہے.لاریب تمام عالم
اسلامی کو ان بزرگوں کا دلی شکر گزار ہونا چاہیے.وجزاھم اللہ احسن الجزاء
اوپر کی چھ مشہور کتابوں کے علاوہ حدیث کی مندرجہ ذیل دو کتابیں بھی بہت مشہور
(۱) موطا مرتبہ امام مالک ابن انس المدنی ( ولادت ۹۵ھ وفات ۱۷۹ھ)
امام مالک حدیث کے امام ہونے کے علاوہ فقہ کے بھی امام سمجھے جاتے ہیں یعنی وہ فقہ
کے ان چار مشہور اماموں میں سے ہیں جنہیں مسلمانوں کا بیشتر حصہ فقہی امور میں قابل تقلید
خیال کرتا ہے.امام مالک کی فقہ پر عمل کرنے والے مسلمان مالکی کہلاتے ہیں.آنحضرت
صل اللی علم کے قریب ترین زمانہ میں پیدا ہونے اور پھر خاص شہر مدینہ میں تربیت پانے کی وجہ سے
امام مالک کا مقام بھی بہت بلند سمجھا جاتا ہے اور حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی مجدد
صدی دوازدہم نے تو ان کی کتاب موطا کا درجہ اپنے ذوق کے مطابق صحیح بخاری سے بھی بالا
قرار دیا ہے لیکن اس میں شک نہیں کہ موطا ایک بہت بلند پایہ کتاب ہے.(۲) مسند احمد: مرتبه امام احمد بن حنبل البغدادی ( ولادت ۱۶۴ ھ وفات ۲۴۲ھ)
Page 18
6
امام مالک کی طرح امام احمد بن حنبل بھی حدیث اور فقہ ہر دو کے امام سمجھے جاتے ہیں اور ان کی
فقہ پر عمل کرنے والے مسلمان حنبلی کہلاتے ہیں.امام احمد بن حنبل کے فرزند کی بے احتیاطی
کی وجہ سے ان کے مجموعہ میں کمزور حدیثیں بھی راہ پاگئی ہیں ورنہ ان کا اپنا جمع کیا ہوا مجموعہ
نہایت شاندار تھا.فقہ کے باقی دو امام ، امام ابو حنیفہ (ولادت ۸۰ھ وفات ۱۵۰ھ) اور امام شافعی
(ولادت ۱۰۵ھ وفات ۲۰۴ھ) ہیں.امام ابو حنیفہ جن کے مقلدین کی تعداد سب سے زیادہ
ہے.عرف عام میں امام اعظم کہلاتے ہیں اور ان کا درجہ فقہ کے سارے اماموں میں بلند ترمانا
گیا ہے.امام ابو حنیفہ کی توجہ زیادہ تر فقہ کی تدوین کی طرف رہی لیکن امام شافعی کا حدیث کا
مجموعہ بھی جو کتاب الائتم کہلاتا ہے کافی شہرت رکھتا ہے.مشہور ہیں.حدیث کی اقسام:
محدثین نے حدیث کی بہت سی قسمیں قرار دی ہیں.ان میں سے ذیل کی اقسام زیادہ
(1) حدیث قولی : یعنی وہ حدیث جس میں آنحضرت صلی یم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے
الفاظ بیان کئے گئے ہوں مثلاً کوئی صحابی یہ بیان کرے کہ فلاں موقع پر آنحضرت صلی للہ ہم نے یہ
تقریر فرمائی یا فلاں شخص کے ساتھ یہ گفتگو کی یا فلاں صحابی کو یہ حکم دیا وغیرہ وغیرہ.
Page 19
7
(۲) حدیث فعلی: یعنی وہ حدیث جس میں آنحضرت صلی نام کے کسی قول کا ذکر نہ ہو بلکہ
صرف فعل کا ذکر ہو مثلاً یہ کہ آنحضرت صلی الی یکم نے فلاں موقع پر یہ کام کیا یا فلاں دینی فریضہ
اس رنگ میں ادا فرمایا وغیرہ وغیرہ.(۳) حدیث تقریری: یعنی وہ حدیث جس میں آنحضرت صلی اللہ یکم کا کوئی قول یا فعل تو بیان نہ کیا
گیا ہو لیکن یہ ذکر ہو کہ آپ کے سامنے فلاں شخص نے فلاں
کام
کیا یا فلاں بات کہی اور اسے
آپ نے اس کام کے کرنے یا اس بات کے کہنے سے نہیں روکا.دراصل عربی زبان میں ”
تقریر “ کے معنی بولنے کے نہیں ہوتے بلکہ کسی بات کو برقرار رکھنے کے ہوتے ہیں.پس
حدیث تقریری سے وہ حدیث مراد ہے جس میں آنحضرت صلی الی یکم نے کسی صحابی کے فعل یا
قول کو صحیح سمجھتے ہوئے اسے بر قرار رکھا ہو اور اس پر اعتراض نہ فرمایا ہو.(۴) حدیث قدسی: یعنی وہ حدیث جس میں آنحضرت صلی اللہ تم نے خدا تعالیٰ کی طرف کوئی
ارشاد یا فعل منسوب کیا ہو مثلاً یہ فرمایا ہو کہ خدا تعالیٰ نے مجھے اس طرح ارشاد فرمایا ہے اور یہ
بات قرآنی وحی کے علاوہ ہو.(۵) حدیث مرفوع : یعنی وہ حدیث جس کا سلسلہ آنحضرت صلی للی کم تک پہنچتا ہو اور آپ کی
طرف کوئی بات براہ راست منسوب کی گئی ہو کہ آپ نے فلاں موقع پر یہ بات فرمائی.وو
Page 20
8
(1) حدیث موقوف : یعنی وہ حدیث جو آنحضرت صلی اللہ ہم تک پہنچنے کی بجائے کسی صحابی تک
آکر رک جاتی ہو مگر اس حدیث کی نوعیت اور صحابی کا انداز بیان ایسا ہو کہ یہ قیاس کیا جائے
کہ یہ حدیث آنحضرت صلی اللہ ہم سے سنی گئی ہو گی.(۷) حدیث متصل : یعنی وہ حدیث جس کے تمام راوی پوری پوری ترتیب کے ساتھ مذکور
ہوں اور کوئی راوی درمیان میں چھٹا ہوا نہ ہو.(۸) حدیث منقطع : یعنی وہ حدیث جس کا کوئی راوی درمیان میں سے چھٹا ہو اہو جس کی وجہ
سے ایسی حدیث کے حسن و فتح کا اندازہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے.(۹) حدیث صحیح یعنی وہ حدیث جس کے تمام راوی حافظہ اور سمجھ اور دیانت کے لحاظ سے
قابل اعتماد ہوں اور اگر غور کیا جائے تو ایک راوی کو قابل اعتماد سمجھنے کے لئے یہی تین اوصاف
ضروری ہوتے ہیں.(۱۰) حدیث ضعیف: یعنی وہ حدیث جس کا کوئی راوی حافظہ یا سمجھ یادیانت کے لحاظ سے قابل
اعتماد نہ ہو.حتی کہ اگر کسی حدیث کے راویوں میں سے کوئی ایک راوی بھی نا قابل اعتماد ہو گا تو
باوجود اس کے کہ دوسرے راوی قابل اعتماد ہوں یہ حدیث ضعیف سمجھی جائے گی.
Page 21
9
(۱۱) حدیث موضوع: یعنی وہ حدیث جس کے متعلق یہ ثابت ہو جائے کہ وہ کسی دروغ گو
راوی نے اپنی طرف سے وضع کر کے بیان کر دی ہے.(۱۲) اثر : (جس کی جمع آثار ہے) اس روایت کو کہتے ہیں جو صرف کسی صحابی کے قول پر
مشتمل ہو اور اس میں آنحضرت صلی ال نیم کی طرف کوئی بات منسوب نہ کی گئی ہو.اس سے ظاہر
ہے کہ اثر دراصل حدیث کی اقسام میں شامل نہیں ہے بلکہ ایک جداگانہ چیز ہے مگر چونکہ
حدیث کی کتابوں میں بالعموم آثار بھی شامل ہوتے ہیں اس لئے بعض اوقات عام لوگ ان
دونوں اصطلاحوں میں فرق نہیں کرتے.حدیث اور سنت میں فرق:
ایک ضروری بات یاد رکھنی چاہیے کہ گو عام لوگ حدیث اور سنت میں فرق نہیں
کرتے مگر دراصل یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں.حدیث تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
ان افعال یا اقوال کا نام ہے جو راویوں کی زبانی روایت کی بنا پر سینہ بہ سینہ نیچے پہنچے اور پھر
ایک سو یا ڈیڑھ سو یا دو سو یا اڑھائی سو سال کے بعد لوگوں کے سینوں سے جمع کر کے کتابی
صورت میں مرتب کر لئے گئے لیکن اس کے مقابل پر سنت کسی لفظی روایت کا نام نہیں ہے
بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تعامل کا نام ہے جو آپ نے کسی دینی امر میں اختیار
فرمایا اور اپنی نگرانی میں اپنے صحابہ کو اس پر قائم فرما دیا اور پھر اس طرح عملی نمونہ کی
صورت میں یہ تعامل بعد میں آنے والے لوگوں تک پہنچا مثلاً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر
Page 22
10
جب نماز کے متعلق قرآنی احکام نازل ہوتے تو بظاہر ان احکام میں نماز کی پوری پوری تفصیل
صراحتاً درج نہیں تھی کہ دن میں کتنی نمازیں فرض ہیں اور انکا کون کون سا وقت ہے اور ہر
نماز میں کتنی رکعات ہونی چاہیں اور ہر رکعت کس طرح ادا کی جانی ضروری ہے وغیرہ
وغیرہ.اس پر آپ نے خدا تعالیٰ کی وحی خفی کے ماتحت یا خداداد نور نبوت کی روشنی میں صحابہ
کے سامنے ان احکام کا عملی نمونہ پیش کیا اور صحابہ کو اپنی نگرانی میں اس نمونہ پر قائم فرما دیا
اور پھر صحابہ نے آگے اپنے نمونہ کا عملی ورثہ تابعین کو دیا اور تابعین نے آگے یہ سبق اپنے
عملی نمونہ کے ذریعہ تبع تابعین تک پہنچایا اور اس طرح تعامل کی ایک مسلسل زنجیر قائم ہوتی
چلی گئی.پس دراصل سنت حدیث سے ایک بالکل علیحدہ اور جدا گانہ چیز ہے اور حدیث کی
نسبت بہت زیادہ وزن اور پختگی کا پہلور کھتی ہے اس لئے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اسلامی شریعت
کی اصل بنیاد قرآن شریف اور سنت پر ہے کیونکہ قرآن خدا کا کلام ہے اور سنت اس کلام کی
تشریح ہے جو خدا کے رسول نے اپنے عملی نمونہ سے قائم فرمائی اور پھر وہ صحابہ کرام کے عملی
نمونہ کے ذریعہ بعد والی نسل کو پہنچی اور پھر بعد والی نسل سے اس سے بعد والی نسل کو پہنچی اور
اس طرح ایک شمع سے دوسری شمع روشن ہوتی چلی گئی لیکن اس کے مقابل پر حدیث جو قولی
روایات کا مجموعہ ہے (حتی کہ اس کی فعلی اور تقریری حدیثیں بھی دراصل قولی روایات کے
ذریعہ ہی ہم تک پہنچی ہیں) صرف ایک تائیدی گواہ کا رنگ رکھتی ہے.بے شک وہ ایک
زبر دست تائیدی گواہ ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جاسکتا مگر بہر حال اسے وہ بنیادی حیثیت
Page 23
11
حاصل نہیں جو قرآن اور سنت کو حاصل ہے.تاہم اس بات میں ذرہ بھر بھی کلام نہیں کہ
حدیث ایک نہایت اعلیٰ درجہ کا تاریخی اور علمی اور روحانی خزانہ ہے اور جب تک کوئی حدیث
قرآن شریف کی کسی آیت یا کسی صحیح حدیث کے خلاف نہ ہو ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ
قرآنی حكم أطِيعُوا الرَّسُول کے ماتحت اسے قبول کر کے اپنی زندگی کے لئے مشعل راہ بنائے
لیکن افسوس ہے کہ آج کل بعض مسلمان کہلانے والے اس بیش بہا علمی خزانہ کی اہمیت کو کم
کرنے کے درپے ہیں.چالیس حدیثوں کا مجموعہ :
اوپر کے تمہیدی نوٹ کے بعد یہ خاکسار ذیل میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
چالیس منتخب شدہ حدیثوں کے درج کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہے.یہ حدیثیں حدیث
کی مشہور اور مستند کتابوں سے لی گئی ہیں اور ہر حدیث کے نیچے اس کا سلیس اردو ترجمہ لکھ
کر مختصر تشریح بھی درج کر دی گئی ہے.میں امید کرتا ہوں کہ اگر مسلمان مرد اور مسلمان
عورتیں ان چالیس حدیثوں کو یاد کر کے اور ان کے معانی کو اپنے ذہنوں میں محفوظ کر کے
ان پر عمل کریں اور ان سے فائدہ اٹھائیں تو ان شاء اللہ ان کے لئے اور ان کے گھروں کے
لئے برکت اور رحمت اور مغفرت کا موجب ہو گا.چالیس کا عدد اس لئے اختیار کیا گیا ہے
کہ ایک تو وہ قرآن شریف میں تکمیل کی علامت کے طور پر بیان ہوا ہے اور دوسرے ایک
پر
حدیث میں ہمارے آقا صلی للہ یکم فرماتے ہیں کہ
Page 24
12
مَنْ حَفِظَ عَلَى أُمَّتِي أَرْبَعِينَ حَدِيثًا مِنْ أَمْرِ دِينِهَا بَعَثَهُ اللهُ فَقِيها
وَكُنتُ له يَوْمَ الْقِيمَةِ شَافِعًا وَ شَهِيدًا
یعنی جو شخص میری اُمت کی اصلاح اور بہبودی کی غرض سے میری (کم از کم)
چالیس حدیثیں محفوظ کرلے گا اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن ایک عالم دین اور فقیہ کی
صورت میں کھڑا کرے گا اور میں اس کے لئے خدا کے حضور شفاعت کرنے والا اور اس
کے ایمان کا گواہ ہوں گا.اس تمہیدی نوٹ کے بعد میں اپنی انتخاب کردہ چالیس حدیثیں درج ذیل کرتا
ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ اسے میرے لئے اور اس مجموعہ کے پڑھنے والوں کے
لئے فضل اور رحمت اور برکت اور مغفرت کا موجب بنائے.آمین یا ارحم الراحمین
1
: الجامع لشعب الايمان ، السابع عشر من شعب الايمان وهو باب في طلب العلم ، فصل: في فضل العلم وشرف مقداره
، روایت نمبر 1597
Page 25
13
1
چھ شرائط ایمان
حَدَّثَنِي أَبِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَابِ قَالَ...فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ...الإيمان...أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ
وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِهِ
(مسلم کتاب الایمان باب بیان الایمان والاسلام والاحسان....)
ترجمہ : حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی للی نیم
فرماتے تھے کہ ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے
رسولوں پر اور یوم آخر یعنی جزا سزا کے دن پر ایمان لائے اور اس کے علاوہ تو خدا کی تقدیر خیر و
شر پر بھی ایمان لائے.“
تشریح : اس حدیث میں اسلام کی تعلیم کے مطابق ایمان کی تشریح بیان کی گئی ہے
جو چھ بنیادی باتوں پر مشتمل ہے.(اول) اللہ پر ایمان لانا جو دنیا کا واحد خالق و مالک خدا ہونے کی وجہ سے ایمانیات کا
مرکزی نقطہ ہے اور یاد رکھنا چاہیے کہ عربی زبان میں اللہ کا لفظ خدائے واحد کے سوا کسی اور
Page 26
14
کے متعلق استعمال نہیں کیا جاتا اور اس سے مراد ایسی ہستی ہے جو تمام عیوب سے پاک اور تمام
صفات حسنہ سے متصف اور تمام علوم کی حامل اور تمام طاقتوں کا سر چشمہ ہے.(دوم) فرشتوں پر ایمان لانا جو خدا کی ایک نہ نظر آنے والی مگر نہایت اہم مخلوق
ہے.فرشتے خدا کے حکم کے ماتحت اس کار خانہ عالم کو چلانے والے اور خدا کی طرف سے پیدا
کئے ہوئے اسباب کے نگران ہیں اور فرشتے خدا اور اس کے رسولوں کے درمیان پیغام رسانی کا
واسطہ بھی بنتے ہیں.(سوم) خدا کی طرف سے نازل ہونے والی کتابوں پر ایمان لانا جن کے ذریعہ دنیا کو
خدا تعالیٰ کے منشاء کا علم حاصل ہوتا ہے.ان کتابوں میں سے آخری اور دائمی کتاب قرآن
شریف ہے جس نے پہلی تمام شریعتوں کو جو وقتی اور قومی نوعیت کی تھیں منسوخ کر دیا ہے اور
اب قیامت تک قرآن کے سوا کوئی اور شریعت نہیں.(چهارم) خدا کے رسولوں پر ایمان لانا جن پر وقتاً فوقتاً الہامی کتابیں نازل ہوتی رہی
ہیں اور جو اپنے عملی نمونہ سے خدا کے منشاء کو دنیا پر ظاہر کرتے رہے ہیں.ان میں سے آخری
صاحب شریعت نبی اور خاتم النبیین ہمارے آنحضرت صلی اللہ کم ہیں جو سید ولد آدم اور فخر انبیاء
اور افضل الرسل ہیں.(پنجم) یوم آخر پر ایمان لانا جو موت کے بعد آنے والا ہے اور جس میں انسان نئی
زندگی حاصل کر کے اپنے ان اچھے یا برے اعمال کا بدلہ پائے گا جو اس نے دنیا میں کئے ہوں
گے.
Page 27
15
(ششم) تقدیر خیر وشر پر ایمان لانا جو خدا کی طرف سے دنیا میں جاری شدہ قانون کی
صورت میں قائم ہے یعنی اس بات پر یقین رکھنا کہ دنیاکا قانون قدرت اور قانون شریعت ہر دو
خدا کے بنائے ہوئے قانون ہیں اور خدا ہی اس سارے مادی اور روحانی نظام کا بانی اور نگران
ہے.خدا نے ہر کام کے متعلق خواہ وہ روحانی ہے یا مادی یہ اصول مقرر کر رکھا ہے کہ اگر یوں
کرو گے تو اسکا اس اس طرح اچھا نتیجہ نکلے گا اور اگر یوں کروگے تو اس کا اس اس طرح خراب
نتیجہ نکلے گا اور پھر خدا اپنے قانون کا مالک بھی ہے اور ایسے امور میں جو اس کی کسی بیان کردہ
سنت یا وعدہ یا صفت اور پھر خدا کے خلاف نہ ہوں وہ اس قانون میں اپنے رسولوں اور نیک
بندوں کی خاطر خاص حالات میں استثنائی طور پر تبدیلی بھی کر سکتا ہے.چنانچہ معجزات کا سلسلہ
عموماً اسی استثنائی قانون سے تعلق رکھتا ہے.
Page 28
16
2
پانچ ارکان اسلام
عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى
خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ
اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ
الزَّكَاةِ وَالحَج وَصَوْمِ رَمَضَانَ.(صحيح البخاري كتاب الايمان باب دعاؤکم ایمانکم......)
ترجمہ: عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللی علم فرماتے تھے
کہ اسلام کی بنیاد پانچ باتوں پر رکھی گئی ہے.(۱) اس بات کی دل اور زبان سے گواہی دینا کہ اللہ
کے سوا کوئی ہستی قابل پرستش نہیں اور یہ کہ محمد صلی للی کمک خدا کے رسول ہیں.(۲) نماز قائم کرنا
(۳) زکوۃ ادا کر نا (۴) بیت اللہ کا حج بجالانا اور (۵)رمضان کے روزے رکھنا.تشریح یاد رکھنا چاہیے کہ جہاں اُوپر والی حدیث ( یعنی پہلی حدیث) میں ایمان کی
تشریح بیان کی گئی تھی وہاں موجودہ حدیث میں اسلام کی تشریح بیان کی گئی ہے اور ان دونوں
میں فرق یہ ہے کہ ایمان عقیدہ کا نام ہے اور اسلام عمل کا نام ہے اور دین کی تکمیل کے لئے یہ
Page 29
17
دونوں باتیں نہایت ضروری ہیں اور یہ جو ان دونوں حدیثوں میں خدا اور رسول پر ایمان لانے
کو مشترک رکھا گیا ہے اس کی یہ وجہ ہے کہ پہلی حدیث میں تو ایمان باللہ اور ایمان بالرسول کو
صرف دل کے عقیدہ اور زبان کی تصدیق کے اظہار کے لئے شامل کیا گیا ہے مگر دوسری حدیث
میں وہ عمل کی بنیاد بننے کی حیثیت میں داخل کیا گیا ہے.بہر حال موجودہ حدیث کی رو سے
اسلام کی تعریف میں سب سے اول نمبر پر یہ بات رکھی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور
آنحضرت صلی اللہ کم کی رسالت پر ایمان لایا جائے تاکہ ایک مسلمان کا ہر عمل اسی مقدس عقیدہ
کی بنیاد پر قائم ہو کہ خدا ایک ہے اور محمد رسول اللہ صلی ال یکم اس کی طرف سے آخری شریعت
لانے والے نبی ہیں.اس کے بعد چار عملی عباد تیں گنائی گئی ہیں جو یہ ہیں.(۱) پہلی عبادت صلوۃ یعنی نماز ہے جس کے معنی عربی زبان میں دعا اور تسبیح و تحمید
کے ہیں.نماز دن رات کے چوبیس گھنٹوں میں پانچ نمازوں کی صورت میں فرض کی گئی ہے اور
جسمانی طہارت یعنی مسنون وضو کے بعد مقررہ طریق پر ادا کی جاتی ہے.ان پانچ نمازوں میں
سے ایک صبح کی نماز ہے جو صبح صادق کے بعد اور سورج نکلنے سے پہلے پڑھی جاتی ہے.دوسرے ظہر کی نماز ہے جو سورج کے ڈھلنے یعنی دو پہر کے بعد پڑھی جاتی ہے.تیسرے عصر
کی نماز ہے جو سورج کے کافی نیچا ہو جانے کے وقت پڑھی جاتی ہے.چوتھے مغرب کی نماز ہے
جو سورج کے غروب ہونے کے بعد پڑھی جاتی ہے اور پانچویں عشاء کی نماز ہے جو شفق کے
غائب ہونے کے بعد پڑھی جاتی ہے.اس طرح نہ صرف دن کے مختلف اوقات کو بلکہ رات
کے ہر دو کناروں کو بھی خدا کے ذکر اور خدا کی عبادت اور خدا سے اپنی دعاؤں کی طلب میں
Page 30
18
خرچ کیا جاتا ہے.نماز کی غرض و غایت خدا تعالیٰ سے ذاتی تعلق پیدا کرنا اور اس کی یاد کو اپنے
دل میں تازہ رکھنا اور اس کے ذریعہ اپنے نفس کو فحشاء اور منکرات سے پاک کرنا اور خدا سے
اپنی حاجتیں طلب کرنا ہے اور آنحضرت صلی اللہ نام کے ایک ارشاد کے مطابق کامل نماز وہ ہے
جس میں نماز پڑھنے والا اس وجد ان سے معمور ہو کہ میں خدا کو دیکھ رہا ہوں یا کم از کم یہ کہ خدا
مجھے دیکھ رہا ہے.نماز کے اوقات میں انسانی زندگی کے مختلف حصوں کی طرف لطیف اشارہ
رکھا گیا ہے اور اسی لئے دن کے آخری حصہ میں جب رات کی تاریکی قریب آرہی ہوتی ہے
نمازوں کے درمیانی وقفہ کو کم کر دیا گیا ہے تا کہ اس بات کی طرف اشارہ کیا جائے کہ عالم
آخرت کی تیاری عمر کی زیادتی کے ساتھ تیز سے تیز تر ہوتی چلی جانی چاہیے.نماز کی عبادت
حقیقتا روحانیت کی جان ہے اور اسی لئے اسے مومن کا معراج قرار دیا گیا ہے اور نماز کے ساتھ
آنحضرت علی ال مل کے ذاتی شغف اور ذاتی سرور کا یہ عالم تھا کہ آپ اکثر فرمایا کرتے تھے
وو
جُعِلَتْ قُرْةُ عَيْنِي فِي الصَّلوة ا، یعنی نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے.(۲) دوسری عملی عبادت اسلام میں زکوۃ ہے جس کے معنی کسی چیز کو پاک کرنے
اور بڑھانے کے ہیں.زکوۃ کی بڑی غرض یہ ہے کہ ایک طرف امیروں کے مال میں سے
غریبوں کا حق نکال کر اسے پاک کیا جائے اور دوسری طرف غریبوں اور بے سہارالوگوں کی
امداد کا سامان مہیا کر کے قوم کے مقام کو بلند کیا جائے اور اس کے افراد کو اوپر اٹھایا جائے.زکوۃ کا ٹیکس مال کا ضروری اور اقل حصہ چھوڑ کر زائد مال پر جسے شرعی اصطلاح میں نصاب
1 : سنن نسائی کتاب عشرۃ النساء باب حب النساء
Page 31
19
کہتے ہیں لگایا جاتا ہے.یہ ٹیکس چاندی، سونے اور چاندی سونے کے زیورات اور چاندی سونے
کے سکوں (جن میں کرنسی نوٹ بھی شامل ہیں) اڑھائی فیصد سالانہ کے حساب سے مقرر ہے
مگر یاد رکھنا چاہیے کہ سونے کا علیحدہ نصاب مقرر نہیں ہے بلکہ چاندی کے نصاب کی قیمت کی
بنیاد پر ہی سونے کے نصاب کا فیصلہ کیا جائے گا جو لازماً ان دو دھاتوں کی نسبتی قیمت کے لحاظ
سے بڑھتا گھٹتار ہے گا.تجارتی مال پر بھی اڑھائی فی صد سالانہ کی شرح مقرر کی گئی ہے.زرعی
زمینوں اور باغات کی فصل پر بارانی فصل کی صورت میں دسواں حصہ اور مصنوعی آبپاشی کی
صورت میں بیسواں حصہ زکوۃ مقرر ہے.بھیڑ بکریوں کی صورت میں قطع نظر تفصیلات کے
ہر چالیس بکریوں سے لے کر ایک سو میں بکریوں تک پر ایک بکری اور گائے اور بھینسوں کی
صورت میں تیں جانوروں پر ایک بچھڑا اور اونٹوں کی صورت میں ہر پانچ اونٹوں پر ایک
بکری اور چھپیں اونٹوں پر ایک جوان اونٹنی مقرر ہے اور زمین کی کانوں اور دفینوں اور بند
خزانوں پر بیس فیصد یک مشت کی شرح سے زکوۃ لگتی ہے اور پھر زکوۃ کی یہ سب آمدنی فقراء
اور مساکین کے علاوہ مقروضوں اور مسافروں اور غلاموں اور مؤلفۃ القلوب لوگوں اور دینی
مہموں میں حصہ لینے والوں اور زکوۃ کا انتظام کرنے والے عملہ پر خرچ کی جاتی ہے.اس طرح
زکوۃ قومی دولت کو سمونے کا بھی ایک بڑا ذریعہ ہے.(۳) تیسری عملی عبادت حج ہے.حج کے معنی کسی مقدس مقام کی طرف سفر اختیار
کرنے کے ہیں اور اسلامی اصطلاح میں اس سے مراد مکہ مکرمہ میں جاکر خانہ کعبہ اور صفا و مروہ کی
پہاڑیوں کا طواف کرنا اور پھر مکہ سے نومیل پر عرفات کے تاریخی میدان میں وقوف کر کے
Page 32
20
دعائیں کرنا اور پھر واپسی پر مزدلفہ میں قیام کر کے عبادت بجالانا اور بالآخر مکہ سے تین میل پر منی
کے مقام میں قربانی دینا ہے.حج جو ماہ ذوالحجہ کی آٹھویں اور نویں اور دسویں تاریخوں میں ہوتا ہے
صرف ایک مقدس ترین جگہ کی زیارت ہی نہیں جس کے ساتھ حضرت ابراہیم اور حضرت
اسماعیل کی قربانی اور پھر خود آنحضرت صلی للی کم کی ابتدائی قربانی کی مقدس روایات وابستہ ہیں بلکہ
حج مختلف ملکوں اور مختلف قوموں کے مسلمانوں کے آپس میں ملنے اور تعارف پیدا کرنے اور ایک
دوسرے سے ملی معاملات میں مشورہ کرنے کا بے نظیر موقع بھی مہیا کرتا ہے.حج ساری عمر میں
صرف ایک دفعہ بجالا نا فرض ہے اور جیسا کہ دوسری حدیث میں صراحت آئی ہے اس کے لئے
صحت اور واجبی خرچ اور راستہ میں امن کا ہوناضروری شرط ہے.(۴) چوتھی عملی عبادت رمضان کے روزے ہیں.یہ روزے ہر ایسے مسلمان پر جو
بلوغ کی عمر کو پہنچ چکا ہو اور بیمار یا مسافر نہ ہو، فرض کئے گئے ہیں.بیمار یا مسافر کو دوسرے ایام میں
گفتی پوری کرنی پڑتی ہے.روزہ کے لئے عربی میں صوم کا لفظ استعمال ہوتا ہے جس کے معنی اپنے
نفس کو روکنے کے ہیں.یہ عبادت رمضان کے مہینہ میں جو قمری حساب کے مطابق سال کے
مختلف موسموں میں چکر لگاتا ہے ادا کی جاتی ہے اور صبح صادق سے قبل سحری کا کھانا کھا کر غروب
آفتاب تک کھانے پینے اور بیوی کے ساتھ اختلاط کرنے سے پر ہیز کیا جاتا ہے.گویا روزوں میں
مسلمانوں کی طرف سے زبانِ حال سے اپنی ذات اور اپنی نسل کی قربانی کا نمونہ پیش کیا جاتا ہے.روزے نفس کو پاک کرنے اور مشقت کا عادی بنانے کے علاوہ غریبوں کی غربت کا احساس پیدا
Page 33
21
کر انے اور مومنوں میں قربانی کی روح کو ترقی دینے کے لئے مقرر کئے گئے ہیں.حقیقتا روزہ ایک
بہت ہی بابرکت عبادت ہے.
Page 34
22
3
آنحضرت صلی
العلم کی پانچ خصوصیات
أَخْبَرَنَا جَابِرُ بْن عَبْدِ اللهِ، أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أُعْطِيتُ خَمْسًا
لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ
مَسْجِدًا وَطَهُورًا...وَأُحِلَّتْ لِي الغَنَائِمُ وَلَمْ تَحِلُّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، وَأُعْطِيتُ
الشَّفَاعَةَ، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةٌ وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةٌ
(صحيح البخاري كتاب التيمم)
ترجمہ : جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی الیم فرماتے ہیں
کہ مجھے خدا کی طرف سے پانچ ایسی باتیں عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی اور نبی کو عطا نہیں
ہوئیں.اوّل مجھے ایک مہینے کی مسافت کے اندازے کے مطابق خداداد رعب عطا کیا گیا ہے.دوسرے میرے لئے ساری زمین مسجد اور طہارت کا ذریعہ بنادی گئی ہے.تیسرے میرے لئے
جنگوں میں حاصل شدہ مال غنیمت جائز قرار دیا گیا ہے حالانکہ مجھ سے پہلے وہ کسی کے لئے جائز
Page 35
23
نہیں تھا.چوتھے مجھے خدا کے حضور شفاعت کا مقام عطا کیا گیا ہے اور پانچویں مجھ سے پہلے ہر
نبی صرف ایک خاص قوم کے لئے مبعوث ہو تا تھا لیکن میں ساری دنیا اور سب قوموں کے لئے
مبعوث کیا گیا ہوں.تشریح: اس حدیث میں ہمارے آقا فداہ نفسی) کی پانچ ممتاز خصوصیات بیان کی گئی
ہیں جس سے آپ کی ارفع شان اور آپ پر خدا تعالیٰ کی غیر معمولی شفقت کا ثبوت ملتا ہے.پہلی خصوصیت آپ کی یہ ہے کہ آپ کو ایک مہینہ کی مسافت کے اندازے کے
مطابق خداداد رعب عطا کیا گیا.چنانچہ تاریخ اسلام اس بات کی زبر دست شہادت پیش کرتی
ہے کہ کس طرح آنحضرت صلی للی علم کی بظاہر کمزوری اور فقر کی حالت کے باوجود ہر دشمن آپ
کے خداداد رعب سے کانپتا تھا حتی کہ بسا اوقات ایسا ہوا کہ دشمن نے مدینہ پر حملہ کرنے کا
ارادہ کیا مگر جب آنحضرت صلی للی علم صحابہ کی ایک قلیل جماعت لے کر اس کے مقابلے کے
واسطے نکلے تو وہ آپ کی آمد کی خبر سنتے ہی بھاگ گیا.پھر جب آنحضرت صلی اللہ ہم نے اس زمانہ
کے سب سے بڑے بادشاہ قیصر روم کو ایک تبلیغی خط لکھا تو اس نے آپ کے حالات سن کر کہا
کہ اگر میں اس نبی کے پاس پہنچ سکوں تو آپ کے پاؤں دھونے میں اپنی سعادت سمجھوں'.دوسری خصوصیت آپ کی یہ ہے کہ آپ کے لئے ساری زمین مسجد بنادی گئی جس
کے نتیجہ میں ایک مسلمان جہاں بھی اسے نماز کا وقت آجائے اپنی نماز ادا کر سکتا ہے اور
دوسری قوموں کی طرح اسے کسی خاص جگہ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے.یہ اس لئے ضروری تھا
1 : بخاری کتاب تفسير القرآن باب قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا
سة
Page 36
24
تا کہ مسلمانوں کے وسیع مجاہد انہ پروگرام میں سہولت پیدا کی جائے.اسی طرح آپ کے لئے
زمین طہارت کا ذریعہ بھی بنادی گئی جس کا ادنی پہلو یہ ہے کہ اگر پانی نہ ملے تو ایک مسلمان وضو
کی جگہ پاک مٹی کے ساتھ تیم کر کے نماز ادا کر سکتا ہے اور یہ پانی اور مٹی کا جوڑ حضرت آدم کی
خلقت کے پیش نظر رکھا گیا ہے جنہیں قرآنی محاورہ کے مطابق گیلی مٹی سے پیدا کیا گیا تھا.تیسری خصوصیت آپ کی یہ ہے کہ بخلاف سابقہ شریعتوں کے جن میں غنیمت کے
مال کو جلا دینے کا حکم تھا.آپ کے واسطے جنگوں میں ہاتھ آنے والا مال غنیمت حلال کیا گیا ہے
جس میں یہ حکمت ہے کہ ایک تو قوموں کے اموال یو نہی ضائع نہ ہوں اور دوسرے ظالم
لوگوں کو یہ سبق دیا جائے کہ اگر تم دوسروں پر دست درازی کروگے تو تمہارے اموال تم سے
چھین کر مظلوموں کے ہاتھ میں دے دیئے جائیں گے اور تیسرے یہ کہ اسلامی غزوات میں
کمزور مسلمانوں کے لئے مضبوطی کا سامان پیدا کیا جائے.چوتھی خصوصیت آپ کی یہ ہے کہ آپ کو شفاعت کا ارفع مقام عطا کیا گیا ہے.شفاعت کے لفظی معنی جوڑ کے ہیں اور اصطلاحی طور پر اس سے مراد عام دعا نہیں ہے بلکہ وہ
مخصوص مقام مراد ہے جس میں ایک مقرب انسان اپنے ڈہرے تعلق کی بنا پر (یعنی ایک
طرف خدا کا تعلق اور دوسری طرف بندوں کا تعلق) خدا کے حضور سفارش کرنے کا حق
حاصل کرتا ہے اور اس سفارش کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے خدا! میں ایک طرف تیرے
ساتھ اپنے خاص تعلق کا واسطہ دے کر اور دوسری طرف تیری مخلوق کے لئے (یا فلاں
مخصوص فرد کے لئے) اپنے قلبی درد کو تیرے سامنے پیش کر کے تجھ سے عرض کرتاہوں کہ
Page 37
25
اپنے ان کمزور بندوں پر رحم فرما اور انہیں بخش دے.چنانچہ آنحضرت صلی ہیں کم ایک دوسری
حدیث میں فرماتے ہیں کہ جب قیامت کے دن لوگوں میں انتہائی گھبر اہٹ اور اضطراب کی
کیفیت پیدا ہو گی تو اس وقت وہ تمام دوسری طرفوں سے مایوس ہو کر میرے پاس آئیں گے اور
پھر میں خدا کے حضور ان کی شفاعت کروں گا اور میری شفاعت قبول کی جائے گی.پانچویں خصوصیت آپ کی یہ ہے کہ جہاں گزشتہ نبی صرف خاص خاص قوموں کی
طرف اور خاص خاص زمانوں کے لئے آئے تھے وہاں آپ ساری قوموں اور سارے زمانوں
کے واسطے مبعوث کئے گئے ہیں.یہ ایک بڑی خصوصیت اور بہت بڑا امتیاز ہے جس کے نتیجہ
میں آپ کا خداداد مشن ہر قوم اور ہر ملک اور ہر زمانہ کے لئے وسیع ہو گیا اور آپ خدا کے کامل
اور مکمل مظہر قرار دیئے گئے ہیں یعنی جس طرح ساری دنیا کا خدا ایک ہے اسی طرح آپ کی
بعثت سے ساری دنیا کا نبی ایک ہو گیا.اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَبَارِكَ وَسَلِّمْ
Page 38
26
4
آنحضرت صلی اليوم
م
آخری شریعت لانے والے نبی ہیں
سمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله صلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِلى آخِرُ
الأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ مَسْجِدِى هذا آخرُ الْمَسَاجِدِ.(مرشد ذوى الحجاء والحاجه (شرح ابن ماجه ، کتاب الاذان، باب ماجاء في فضل الصلاة )
ترجمہ : ابوہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی ا یکم فرماتے تھے کہ
میں آخری نبی ہوں اور میری یہ (مدینہ کی) مسجد آخری مسجد ہے.تشریح : اس لطیف حدیث میں ہمارے آقا آنحضرت صلی اللہ یکم فرماتے ہیں کہ میں
آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی ایسا مصلح نہیں آسکتا جو میری نبوت کے دور کو منسوخ
کر کے اور میرے مقابل پر کھڑ ا ہو کر ایک نیا دور شروع کر دے بلکہ اگر کوئی آئے گا تو وہ لازماً
میرا تابع اور میر اشاگرد اور میری شریعت کا خادم ہونے کی وجہ سے میری نبوت کے دور کے
اندر ہو گا نہ کہ اس سے باہر.اس لطیف مضمون کو واضح فرمانے کے لئے ہمارے آقا صلی ا ہم نے
Page 39
27
یہ الفاظ زیادہ فرمائے ہیں کہ مَسْجِدِى هذا آخِرُ الْمَسَاجِدِ یعنی ”میری یہ (مدینہ والی) مسجد
آخری مسجد ہے.اب ظاہر ہے کہ ان الفاظ کا یہ مطلب ہر گز نہیں ہو سکتا اور نہ ہی واقعات
اس کی تائید کرتے ہیں کہ آئندہ دنیا میں کوئی اور مسجد بنے گی ہی نہیں بلکہ اس کا مطلب صرف
یہ ہے کہ آئندہ کوئی مسجد میری مسجد کے مقابل پر نہیں بنے گی بلکہ جو مسجد بھی بنے گی وہ میری
اس مسجد کے تابع اور اس کی نقل اور ظل ہو گی.ن الله
اسی طرح إِنِّي آخِرُ الأَنْبِيَاءِ ( میں آخری نبی ہوں) کے بھی یہی معنی ہیں کہ آئندہ
کوئی ایسا نبی نہیں آسکتا جو میری غلامی سے آزاد ہو کر میری نبوت کے مقابل پر کھڑا ہو اور
میرے دین کو چھوڑ کر کوئی نیا دین لائے بلکہ اگر کوئی آئے گا تو میر اخادم اور میر اشاگرد اور میرا
تابع اور میر اظل اور گویا میرے وجود کا حصہ ہو کر آئے گا اور یہی وہ گہر ا فلسفہ ہے جو ایک
قرآنی آیت میں آنحضرت صلی للی نیم کا نام خاتم النبيين (نبیوں کی مہر ) رکھ کر بیان کیا گیا ہے.خوب غور کرو کہ اگر آنحضرت صلی علم کی مدینہ والی مسجد کے بعد اسلامی ممالک میں کروڑوں
مسجدوں کی تعمیر کے باوجود مَسْجِدِى هذا آخِرُ الْمَسَاجِدِ ( یعنی میری یہ مسجد آخری مسجد
ہے) کا مفہوم قائم رہتا ہے تو آنحضرت صلی اللہ ظلم کی امت میں آپ کے کسی خادم اور شاگرد اور
تابع کا آپ کی اتباع اور غلامی میں نبوت
کا انعام پانا کس طرح ختم نبوت يا إِنِّي آخِرُ الأَنْبِيَاءِ
(یعنی میں آخری نبی ہوں) کے منشاء کے خلاف قرار دیا جاسکتا ہے؟
پس یقینا اس حدیث کا یہی مطلب ہے کہ میں خدا کا آخری صاحب شریعت نبی ہوں
جس کے بعد کوئی نبی میری غلامی کے جوئے سے آزاد ہو کر اور میرے دین کو چھوڑ کر نہیں
Page 40
28
آسکتا اور میری یہ مسجد آخری مسجد ہے جس کے بعد کوئی اور مسجد میری مسجد کے مقابل پر
نہیں بن سکتی اور اگر غور کیا جائے تو آنحضرت علی علیم کی ارفع شان بھی اس بات میں نہیں ہے
کہ آپ کو گزشتہ جاری شدہ نعمتوں کا بند کرنے والا قرار دیا جائے بلکہ آپ کی شان اس بات
میں ہے کہ الگ الگ نہروں کو بند کر کے آئندہ تمام نہریں آپ کے وسیع دریا سے نکالی جائیں.یہی وہ لطیف تشریح ہے جو اسلام کے چوٹی کے علماء اور بڑے بڑے مجدد ہر زمانہ میں
کرتے آئے ہیں.چنانچہ صوفیاء کے سردار اور امام حضرت شیخ اکبر محي الدين ابن عربی
( ولادت ۵۶۰ھ وفات ۶۳۸ھ) فرماتے ہیں.النُّبُوَّةُ الَّتِي انْقَطَعَتْ بِوُجُودِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا هِيَ نُبُوَّةُ
التشريع
فتوحات مکیه ، باب الثالث والسبعون في معرفة عدد ما يحمل من الاسرار جلد 2 صفحه 6)
سة
یعنی وہ نبوت جس کا دروازہ آنحضرت صلی اللی کام کے وجود سے بند ہو گیا ہے وہ صرف
شریعت والی نبوت ہے.“
حضرت امام عبد الوہاب شعرانی (وفات ۹۷۶ھ) جو ایک بڑے امام مانے گئے ہیں
فرماتے ہیں.إن مطلق النبوة لم يَرْتَفِعُ وَإِنَّمَا ارْتَفَعَ نُبُوهُ التَّصْرِيح
الیواقیت والجواہر ، المبحث ثالث و ثلاثون فى بيان بداية النبوة ، جلد اوّل صفحہ 346)
Page 41
29
یعنی آنحضرت صلی علیہ یکم کی بعثت سے مطلق نبوت ختم نہیں ہوئی بلکہ صرف شریعت والی
نبوت بند ہوئی ہے.“
حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی ( وفات ۱۰۳۴ھ) جو اسلام کے مجد دین میں
نہایت ممتاز حیثیت کے مالک ہیں فرماتے ہیں.حصول کمالات نبوت مرتابعان را بطریق تبعیت و وراثت بعد از
بعثت خاتم الرسل على جميع الانبياء و الرسل الصلوة و التحيات منافى
ختمیت او نیست عليه وعلى آله الصلوة والسلام فَلَا تَكُن مِّنَ الْمُمْتَرِينَ
المكتوبات الربانیہ جلد نمبر ا مکتوب نمبر 301 الی مولانا امان الله فی بیان قرب النبوة )
یعنی آنحضرت صلی ایام کے بعد آپ کے متبعین کے لئے آپ کی پیروی اور ورثہ میں
نبوت کے کمالات کا حصول آپ کے خاتم النبیین ہونے کے منافی نہیں ہے.پس تو اس بات
میں شک کرنے والوں میں سے مت بن.“
حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی مجدد صدی دواز دہم (ولادت ۱۱۴ اھ وفات
۷۶ا اھ ) جن کے علم و فضل اور علو مرتبت کا سکہ دنیاما نتی ہے فرماتے ہیں.حيمَ بِهِ النَّبِيُّون الى لا يُوجَدُ بَعْدَهُ مَنْ يَأْمُرُهُ اللهُ سُبْحَانَهُ بِالشَّرِيعَ عَلَى النَّاسِ
تفهيمات الهيه ، ذکر سیدنا محمد : تفهیم نمبر 54 جلد 2 صفحه85 )
یعنی آنحضرت صلی للی علم پر نبوت کے ختم ہونے کے یہ معنی ہیں کہ آپ کے بعد کوئی
ایسا شخص نہیں آسکتا جسے خدا تعالیٰ کوئی نئی شریعت دے کر مبعوث کرے.“
Page 42
30
حضرت مولانا مولوی محمد قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم دیو بند (ولادت ۱۲۴۸ھ وفات
۱۲۹۷ھ ) جو قریب کے زمانہ میں ہی بہت بڑے عالم گزرے ہیں اور ان کا مدرسہ علوم مشرقیہ
کی تعلیم کے لئے بر عظیم ہندو پاکستان میں بہت بڑی شہرت کا مالک ہے فرماتے ہیں.عوام کے خیال میں تورسول اللہ لا علم کا ختم ہونا بایں معنی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء
سابق کے زمانہ کے بعد اور آپ سب میں آخر نبی ہیں مگر اہل فہم پر روشن ہو گا کہ تقدم و تأخر
زمانی میں بالذات کچھ فضیلت نہیں.پھر مقام مدح میں وَلَكِن رَّسُولَ اللهِ وَخَاتَم
النبيين فرمانا اس صورت میں کیونکر صحیح ہو سکتا ہے.اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی صلی کی کوئی
نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہیں آئے گا.“
(تحذیر الناس صفحہ نمبر 3 و نمبر (25)
پس لا ریب یہی نظریہ درست اور صحیح ہے کہ ہمارے آقا آنحضرت صلی نیم کے وجود
باجود میں نبوت اپنے کمال کو پہنچ چکی ہے اور دائمی شریعت کا نزول پورا ہو چکا ہے اور آپ کے
بعد کوئی نبی نہیں مگر وہی جو آپ کا خوشہ چین بن کر آپ کی غلامی میں آپ کی مہر تصدیق کے
ساتھ نبوت کے انعام کا وارث بنتا ہے.کاش لوگ اس لطیف نکتہ کو سمجھیں.☆☆☆
Page 43
31
5
اعمال کا اجر نیت کے مطابق ملتا ہے
عَلْقَمَة بَن وَقَاصِ اللَّيْهِيَ يَقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الخَطَابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ
قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ،
وَإِثْمَالِكُلِ امْرِ مَا نَوَى.(صحیح البخاري كتاب بدء الوحى باب كيف كان بدء الوحي الى رسول الله
ترجمہ : حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ
صلی ایم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اعمال نیتوں کے ساتھ ہوتے ہیں اور ہر شخص اپنی نیت کے
مطابق بدلہ پاتا ہے.تشریح: یہ لطیف حدیث انسانی اعمال کے فلسفہ پر ایک اصولی روشنی ڈالتی ہے.ظاہر
ہے کہ بظاہر نیک نظر آنے والے اعمال بھی کئی قسم کے ہوتے ہیں.بعض کام محض عادت کے
طور پر کئے جاتے ہیں اور بعض کام دوسروں کی نقل میں کئے جاتے ہیں اور بعض کام ریا اور
دکھاوے کے طور پر کئے جاتے ہیں لیکن ہمارے آقا آنحضرت صلی یکم فرماتے ہیں کہ یہ سب
Page 44
32
کام خدائے اسلام کے ترازو میں بالکل بے وزن اور بے سود ہیں اور صحیح عمل وہی ہے جو دل کے
سچے ارادہ اور نیت کے خلوص کے ساتھ کیا جائے اور یہی وہ عمل ہے جو خدا کی طرف سے حقیقی
جزا پانے کا مستحق ہوتا ہے.حق یہ ہے کہ جب تک انسان کا دل اور اس کی زبان اور اس کے
جوارح یعنی ہاتھ پاؤں وغیرہ کسی عمل کے بجالانے میں برابر کے شریک نہ ہوں وہ عمل کچھ
حقیقت نہیں رکھتا.دل میں سچی نیت ہو ، زبان سے اس نیت کی تصدیق ہو اور ہاتھ پاؤں اس
نیت کے عملی گواہ ہوں تو تب جا کر ایک عمل قبولیت کا درجہ حاصل کرتا ہے.اگر کسی شخص
کے دل میں سچی نیت نہیں تو وہ منافق ہے.اگر اس کی زبان پر اس کی نیت کی تصدیق نہیں تو وہ
بزدل ہے اور اگر اس کے ہاتھ پاؤں اس کی بیان کردہ نیت کے مطابق نہیں تو وہ بد عمل ہے.پس سچا عمل وہی ہے جس کے ساتھ سچی نیت شامل ہو.پاک نیت سے انسان اپنے بظاہر دنیوی
اعمال کو بھی اعلیٰ درجہ کے دینی اعمال بنا سکتا ہے.چنانچہ آنحضرت صلی یکم دوسری جگہ فرماتے
ہیں کہ اگر ایک خاوند اس نیت سے اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالتا ہے کہ میرے خدا کا یہ منشاء
ہے کہ میں اپنی بیوی کا خرج مہیا کروں اور اس کے آرام کا خیال رکھوں تو اس کا یہ فعل بھی خدا
کے حضور ایک نیکی شمار ہو گا امگر افسوس ہے کہ دنیا میں لاکھوں انسان صرف اس لئے نماز
پڑھتے ہیں کہ انہیں بچپن سے نماز کی عادت پڑ چکی ہے اور لاکھوں انسان صرف اس لئے روزہ
رکھتے ہیں کہ ان کے ارد گرد کے لوگ روزہ دار ہوتے ہیں اور لاکھوں انسان صرف اس لئے حج
کرتے ہیں کہ تالو گوں میں ان کا نام حاجی مشہور ہو اور وہ نیک سمجھے جائیں اور ان کے کاروبار
1 : بخاری کتاب النفقات باب فضل نفقة على الاهل
Page 45
33
میں ترقی ہو.ہمارے آقا (فداہ نفسی) کی یہ حدیث ایسے تمام اعمال کو باطل قرار دیتی ہے اور
ایک باطل عمل خواہ وہ ظاہر میں کتنا ہی نیک نظر آئے خدا کے حضور کوئی اجر نہیں پاسکتا.لا
ریب سچا عمل وہی ہے جس کے ساتھ سچی نیت ہو اور عمل کا اجر بھی نیت کے مطابق ہی ملتا ہے.
Page 46
34
6
خدا کی نظر دلوں پر ہے
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى
صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ.(صحیح مسلم کتاب البر والصلة باب تحریم ظلم المسلم و خذله.ترجمہ: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول
اللہ صلی الله علم فرماتے تھے
کہ اے مسلمانو! اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور تمہارے مالوں کی طرف نہیں دیکھتا بلکہ
تمہارے دلوں اور تمہارے عملوں کی طرف دیکھتا ہے.تشریح : اس حدیث میں آنحضرت صلی للی یمن نے ایسی دو باتوں کا ذکر فرمایا ہے جو
خدا تعالیٰ کی نعمت ہونے کے باوجود بعض اوقات عورتوں اور مردوں میں بھاری فتنہ کا موجب
بن جاتی ہیں.ان میں سے ایک جسمانی حسن و جمال ہے جو عموماً عورتوں کے لئے فتنہ کی بنیاد بنتا
ہے اور دوسرے مال و دولت ہے جو بالعموم مردوں کو فتنہ میں مبتلا کرتا ہے.ان دو باتوں کو
مثال کے طور پر سامنے رکھ کر آنحضرت صلی می کنم ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک یہ دونوں چیزیں
خدا کی پیدا کی ہوئی نعمتیں ہیں مگر مسلمانوں کو ہوشیار رہنا چاہیے کہ کسی انسان کی قدر و قیمت کو
Page 47
35
پر کھنے کے لئے خدا تعالیٰ عورتوں کے حسن اور مردوں کے مال کی طرف نہیں دیکھتا بلکہ ان
دونوں کے دلوں اور دماغ کی طرف دیکھتا ہے جو انسانی خیالات اور جذبات کا مبد او منبع ہیں اور
پھر ان کے اعمال کی طرف دیکھتا ہے جو ان خیالات اور جذبات کے نتیجہ میں ظہور پذیر ہوتے
اس حدیث میں جو قلب کا لفظ بیان ہوا ہے اس سے دل اور دماغ دونوں مراد ہیں
جنہیں انگریزی میں ہارٹ (Heart) اور مائنڈ (Mind) کہتے ہیں کیونکہ قلب کے لفظی معنی
کسی نظام کے مرکزی نقطہ کے ہیں اور دل اور دماغ دونوں اپنے اپنے دائرہ میں جسمانی نظام کا
مرکز ہیں.دماغ ظاہری احساسات کا مرکز ہے اور دل روحانی جذبات کا مرکز ہے.پس
آنحضرت صلی ا ولم نے اس جگہ قلوب اور اعمال کا لفظ استعمال کر کے اشارہ فرمایا ہے کہ بے شک
جسمانی حسن اور ظاہری مال و دولت بھی خدا کی نعمتیں ہیں اور انسان کو ان کی قدر کرنی چاہیے
لیکن وہ چیز جس کی طرف خدا کی نظر ہے انسان کا قلب اور اس کے اعمال ہیں لہذاہر مسلمان کا
فرض ہے کہ وہ جمال و مال اور دنیا کی دوسری نعمتوں پر فخر کرنے کی بجائے اپنے دل و دماغ کی
اصلاح اور اپنے اعمال کی درستی کی فکر کرے.یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ یہ جو آنحضرت صلی لی یکم نے فرمایا ہے کہ خدا تعالیٰ
انسان کے قلب اور اس کے اعمال کی طرف دیکھتا ہے اس سے صرف یہی مراد نہیں کہ
قیامت والے حساب کتاب میں انہی چیزوں کو وزن حاصل ہو گا بلکہ ان الفاظ میں یہ اشارہ کرنا
بھی مقصود ہے کہ اس دنیا میں بھی حقیقی وزن دل کے جذبات اور دماغ کے احساسات اور
Page 48
36
جوارح کے اعمال کو حاصل ہوتا ہے.حق یہ ہے کہ جس قوم کے افراد کو یہ نعمت حاصل
ہو جائے یعنی ان کا دل اور ان کا دماغ اور ان کے ہاتھ پاؤں ٹھیک رستہ پر چل پڑیں اس کی ترقی
اور اس کے لئے نعمتوں کے حصول کو کوئی طاقت روک نہیں سکتی.
Page 49
37
7
مجاہد اور قائد مسلمان میں درجہ کا فرق
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ آمَنَ
بالله وَبِرَسُولِهِ، وَأَقَامَ الصَّلاةَ، وَصَامَ رَمَضَانَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُدْخِلَهُ
الجَنَّةَ ، جَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ جَلَسَ فِي أَرْضِهِ الَّتِي وُلِدَ فِيهَا، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ
الله : أَفَلَا تُبَشِّرُ النَّاسَ قَالَ: إِنَّ فِي الجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ، أَعَدَّهَا اللهُ
لِلْمُجَاهِدِينَ في سَبِيلِ اللهِ، مَا بَيْنَ اللَّهَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ،
فَإِذَا سَأَلْكُمُ الله فَاسْأَلُوهُ الفِرْدَوْسَ فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الجَنَّةِ وَأَعْلَى الجَنَّةِ - أَرَاهُ
قَالَ وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحمنِ وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الجنة.(صحیح البخاری کتاب الجهاد والسير باب درجات المجاهدين في سبيل الله
ترجمہ : حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی ا یکم فرماتے
تھے کہ جو شخص خدا اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہے اور نماز قائم کرتا اور رمضان کے
Page 50
38
روزے رکھتا ہے اس کے متعلق اللہ تعالیٰ پر گویا یہ حق ہو جاتا ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل
کرے خواہ ایسا انسان خدا کے رستہ میں جہاد کرے یا کہ اپنے پیدائشی گھر کے باغیچہ میں ہی قاعد
بن کر بیٹھار ہے.صحابہ نے عرض کیا.تو کیا یار سول اللہ ! ہم یہ بشارت لوگوں تک نہ پہنچائیں ؟
آپ نے فرمایا.جنت میں ایک سو درجے ایسے ہیں جنہیں خدا نے اپنے مجاہد بندوں کے لئے تیار
کر رکھا ہے اور ہر درجہ میں زمین و آسمان کا فرق ہے.پس اے مسلمانو! جب تم خدا سے جنت
کی خواہش کرو تو فردوس والے درجہ کی خواہش کیا کرو جو جنت کا سب سے وسطی اور سب سے
اعلیٰ درجہ ہے اور اس سے اوپر خدائے ذوالجلال کا عرش ہے اور اسی میں سے جنت کی تمام
نہریں پھوٹتی ہیں.تشریح: میں نے اپنے عام اصول انتخاب کے خلاف یہ لمبی حدیث اس لئے درج کی
ہے کہ اس حدیث سے ہمیں کئی اہم اور مفید اور اصولی باتوں کا علم حاصل ہوتا ہے اور وہ باتیں
یہ ہیں.(۱) یہ کہ جنت میں صرف ایک ہی درجہ نہیں ہے بلکہ بہت سے درجے ہیں جن میں
سے سب سے اعلیٰ درجہ فردوس ہے جو گویا جنت کی نہروں کا منبع ہے.(۲) یہ کہ جنت میں مجاہد مسلمانوں کے کم سے کم درجہ اور قاعد مسلمانوں کے اعلیٰ
سے اعلیٰ درجہ میں بھی اتنا ہی فرق ہو گا جتنا کہ زمین اور آسمان میں فرق ہے.
Page 51
39
(۳) یہ کہ مسلمانوں کو نہ صرف مجاہدوں والا درجہ حاصل کرنے کی کوشش کرنی
چاہیے بلکہ مجاہد وں والے درجوں میں سے بھی سب سے اعلیٰ درجہ یعنی فردوس کو اپنا مقصد بنانا
چاہیے.(۴) یہ کہ جنت کے مختلف درجے خدا تعالیٰ کے قرب کے لحاظ سے مقرر کئے گئے
ہیں اسی لئے جنت کے اعلیٰ ترین درجہ کو عرش الہی کے قریب تر رکھا گیا ہے.(۵) یہ کہ جنت کی نعمتیں مادی نہیں ہیں بلکہ روحانی ہیں کیونکہ ان کا معیار خدا کا
قرب مقرر کیا گیا ہے اور گو ان نعمتوں میں روح کے ساتھ جسم کا بھی حصہ ہو گا جیسا کہ اعمال
میں بھی اس کا حصہ ہوتا ہے مگر جنت میں انسان کا جسم بھی روحانی رنگ کا ہو گا.اس لئے وہاں
کی جسمانی نعمتیں بھی دراصل روحانی معیار کے مطابق بالکل پاک وصاف ہوں گی.یہ وہ لطیف علم ہے جو ہمیں اس حدیث سے حاصل ہوتا ہے اور آنحضرت صلی الی یوم
کے اس ارشاد کا منشاء یہ ہے کہ تا مسلمانوں کے مقصد اور آئیڈیل کو زیادہ سے زیادہ بلند کیا
جائے.بے شک ایک مسلمان جو نماز اور روزہ کے احکام وغیرہ کو تو خلوص نیت سے پورا
کرتا ہے (اس حدیث میں حج اور زکوۃ کے ذکر کو اس لئے ترک کیا گیا ہے کہ وہ ہر مسلمان
پر واجب نہیں بلکہ صرف مستطیع اور مالدار لوگوں پر واجب ہیں) مگر اپنے گھر میں قاعد بن
کر بیٹھا رہتا ہے وہ خدا کی گرفت سے بچ کر نجات حاصل کر سکتا ہے مگر وہ ان اعلیٰ انعاموں
کو نہیں پاسکتا جو انسان کو خدا تعالیٰ کے قرب خاص کا حق دار بناتے ہیں.پس ترقی کی خواہش
رکھنے والے مومنوں کا فرض ہے کہ وہ قاعد انہ زندگی ترک کر کے مجاہدانہ زندگی اختیار
Page 52
40
کریں اور خدا کے دین اور اس کے رسول کی امت کی خدمت میں دن رات کوشاں رہیں.حق یہ ہے کہ ایک قاعد مسلمان جس کے دین کا اثر اور اس کے دین کا فائدہ صرف اس کی
ذات تک محدود ہے وہ اپنے آپ کو اعلیٰ نعمتوں سے ہی محروم نہیں کرتا بلکہ اپنے لئے ہر
وقت کا خطرہ بھی مول لیتا ہے کیونکہ بوجہ اس کے کہ وہ بالکل کنارے پر کھڑا ہے.اس کی
ذرا سی لغزش اسے نجات کے مقام سے نیچے گرا کر عذاب کا نشانہ بنا سکتی ہے مگر ایک مجاہد
مسلمان اس امکانی خطرہ سے بھی محفوظ رہتا ہے.باقی رہا یہ سوال کہ خدا کی راہ میں مجاہد بننے کا کیا طریق ہے ؟ سو گو جہاد فی سبیل اللہ کی
بیسیوں شاخیں ہیں مگر قرآن شریف نے دو شاخوں کو زیادہ اہمیت دی ہے.چنانچہ فرماتا ہے.-
فَضَّل اللهُ الْمُجَاهِدِ بْنَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ
عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً
1
یعنی خدا تعالیٰ نے دین کے رستہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ذریعہ جہاد کرنے
والے لوگوں کو گھروں میں بیٹھ کر نیک اعمال بجالانے والوں پر بڑی فضیلت دی ہے.“
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جہاد کا بڑا ذریعہ مال اور جان ہے.مال کا جہاد یہ ہے کہ
اسلام کی اشاعت اور اسلام کی ترقی اور اسلام کی مضبوطی کے لئے بڑھ چڑھ کر روپیہ خرچ کیا
1 : النساء : 96
Page 53
41
جائے اور جان کا جہاد یہ ہے کہ اپنے وقت کو زیادہ سے زیادہ دین کی خدمت (یعنی تبلیغ اور
تربیت وغیرہ) میں لگایا جائے اور موقع پیش آنے پر جان کی قربانی سے بھی دریغ نہ کیا
جائے.جو شخص ان دو قسموں کے جہادوں میں دلی شوق کے ساتھ حصہ لیتا ہے وہ خدا کی
طرف سے ان اعلیٰ انعاموں کا حق دار قرار پاتا ہے جو ایک مجاہد کے لئے مقدر ہیں مگر گھر
میں بیٹھ کر نماز ، روزہ کرنے والا مسلمان ایک قاعد والی بخشش سے زیادہ امید نہیں رکھ سکتا.دیکھو کہ ہمارے آقا صلی علیہ کم کی ہم پر کس درجہ شفقت ہے کہ ایک انتہائی طور
پر رحیم باپ کی طرح فرماتے ہیں کہ بے شک نماز، روزہ کے ذریعہ نجات تو پالو گے اور
عذاب سے بچ جاؤ گے مگر اپنے تخیل کو بلند کر کے ان انعاموں کو حاصل کرنے کی کوشش
کرو جو ایک مجاہد فی سبیل اللہ کے لئے مقدر کئے گئے ہیں کیونکہ اس کے بغیر قومی زندگی کا
قدم کبھی بھی ترقی کی بلندیوں کی طرف نہیں اٹھ سکتا بلکہ ایسی قوم کی زندگی ہمیشہ خطرے
میں رہے گی.اس تعلق میں سب سے مقدم فرض ماں باپ کا اور ان سے اتر کر سکولوں
کے اساتذہ اور کالج کے پروفیسروں کا ہے کہ وہ بچپن کی عمر سے ہی بچوں میں مجاہدانہ روح
پیدا کرنے کی کوشش کریں اور انہیں قاعد انہ زندگی پر ہر گز قانع نہ ہونے دیں.
Page 54
42
8
ہر نا پسندیدہ بات دیکھ کر اصلاح کی
کوشش کرو
فَقَالَ أَبُو سَعِيد...سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ رَأَى
مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيْرُهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ
فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَف الإيمان.(صحیح مسلم کتاب الایمان باب بيان كون النهي عن المنكر من ايمان
ترجمہ: ابوسعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ نیلم کو فرماتے
سنا ہے کہ تم میں سے جو شخص کوئی خلاف اخلاق یا خلاف دین بات دیکھے تو اسے چاہیے کہ اس
بات کو اپنے ہاتھ سے بدل دے لیکن اگر اسے یہ طاقت حاصل نہ ہو تو اپنی زبان سے اس کے
متعلق اصلاح کی کوشش کرے اور اگر اسے یہ طاقت بھی نہ ہو تو کم از کم اپنے دل میں اسے برا
سمجھ کر ( دعا کے ذریعہ) بہتری کی کوشش کرے اور آپ فرماتے تھے کہ یہ سب سے کمزور قسم
کا ایمان ہے.
Page 55
43
تشریح: جہاں اوپر والی حدیث میں جہاد فی سبیل اللہ کی تحریک کی گئی ہے اور بتایا
گیا ہے کہ کس طرح ہر سچے مومن کو اپنے مال اور اپنی جان کے ذریعہ ہر وقت جہاد میں لگے
رہنا چاہیے وہاں اس حدیث میں جہاد کے بہت سے میدانوں میں سے ایک میدان کے متعلق
جہاد کا طریق کار بیان کیا گیا ہے.یہ میدان قومی اور خاندانی اور انفرادی اصلاح سے تعلق
رکھتا ہے.آنحضرت صلی اللہ یکم فرماتے ہیں کہ بہت سی دینی اور اخلاقی بدیاں اس لئے پھیلتی ہیں
کہ لوگ انہیں دیکھ کر خاموشی اختیار کرتے ہیں اور ان کی اصلاح کے لئے قولی یا عملی قدم
نہیں اٹھاتے.اس طرح نہ صرف بدی کا دائرہ وسیع ہوتا جاتا ہے کیونکہ ایک شخص کے
برے نمونہ سے بیسیوں مزید آدمی خراب ہوتے ہیں بلکہ لوگوں کے دلوں میں سے بدی کا
رعب بھی کم ہونے لگتا ہے.ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ قانونی طریق کے علاوہ سوسائٹی میں سے بدی کو مٹانے کے
دو ہی بڑے ذریعے ہیں.ایک ذریعہ بزرگوں اور نیک لوگوں کی نگرانی اور نصیحت ہے جو بے
شمار کمزور طبیعتوں کو سنبھالنے کا موجب ہو جاتی ہے اور دوسرا ذریعہ بدی کا وہ رعب اور ڈر
ہے جو سوسائٹی کی رائے عامہ کے نتیجہ میں پیدا ہوتا ہے اور یہ بھی لا تعداد لوگوں کو بدی کے
ار تکاب سے روک دیتا ہے مثلاً ایک بچہ بد صحبت میں مبتلا ہو کر خراب ہونے لگتا ہے مگر اس
کے والد یا والدہ یا کسی اور نیک بزرگ کی بر وقت نگرانی اور نصیحت اسے گرتے گرتے سنبھال
لیتی ہے یا ایک شخص اپنے اندر ایک خاص قسم کی بدی کی طرف میلان پیدا کر نا شروع کر دیتا
ہے مگر اسے سوسائٹی کا رعب اور بدنامی کا ڈر اس میلان سے روک کر پھسلنے سے بچالیتا ہے.
Page 56
44
اسی طرح اگر عملی نگرانی یا قولی نصیحت نہ بھی ہو تو نیک لوگوں کی خاموش دعائیں بھی
خاندانوں اور قوموں کی اصلاح میں بڑا کام کرتی ہیں.پس اس حدیث میں آنحضرت صلی للی کم
ان تینوں قسموں کے موجبات اصلاح کو حرکت میں لا کر مسلمانوں میں بدی کا رستہ بند کرنا
اور نیکی کارستہ کھولنا چاہتے ہیں.دنیا میں اکثر لوگ ایسے ست اور غافل اور بے پرواہ ہوتے
ہیں کہ ان کی آنکھوں کے سامنے ان کا کوئی عزیز یا دوست یا ہمسایہ بر ملا طور پر ایک خلاف
اخلاق یا خلاف دین حرکت کرتا ہے مگر وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے اور یہ خیال کر کے کہ ہم
کسی عزیز یا دوست کا دل میلا کیوں کریں یا ہم کسی سے جھگڑا مول کیوں لیں یا ہمیں دوسروں
کے ذاتی اخلاق سے کیا سروکار ہے بالکل بے حرکت بیٹھے رہتے ہیں اور بدی ان کی آنکھوں
کے سامنے جڑ پکڑتی اور پودے سے پیڑ اور پیڑ سے درخت بنتی چلی جاتی ہے مگر ان کے کانوں
پر جوں تک نہیں رینگتی.یہ نادان اتنا نہیں سمجھتے کہ جو آگ آج ان کے ہمسایہ کے گھر میں
لگی ہے کل کو وہی وسیع ہو کر ان کے اپنے گھر کو بھی تباہ کر دے گی.الغرض ہمارے آقا آنحضرت صلی اللہ تم نے کمال حکمت اور دور اندیشی سے یہ ارشاد
فرمایا ہے کہ تم اپنے ارد گرد بدی اور گناہ کی آگ دیکھ کر تماشہ بین بن کر نہ بیٹھے رہو بلکہ اولاً
اپنے ہمسایہ کے گھر کو اور پھر خود اپنے گھر کو بھی اس آگ کی تباہی سے بچاؤ اور آپ نے اس
تبلیغی اور تربیتی جد وجہد کو تین درجوں میں منقسم فرمایا ہے.اوّل یہ کہ انسان کو اگر طاقت ہو
تو بدی کو اپنے ہاتھ سے روک دے.دوسرے یہ کہ اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ ہو تو
Page 57
45
زبان کے ذریعہ نصیحت کر کے روکنے کی کوشش کرے اور تیسرے یہ کہ اگر اس کی بھی
طاقت نہ ہو تو پھر دل کے ذریعہ سے روکے.یاد رکھنا چاہیے کہ اس جگہ ہاتھ سے روکنے سے غیر اور لا تعلق لوگوں کے خلاف
تلوار چلانا یا جبر کر نامراد نہیں بلکہ مراد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس پوزیشن میں ہو کہ وہ کسی
بدی کو اپنے ہاتھ کے زور سے بدل سکے تو اس کا فرض ہے کہ ایسا کرے مثلاً اگر ایک باپ
اپنے بچے کو کسی غلط رستہ پر پڑتا دیکھے یا ایک افسر اپنے ماتحت کو یا آقا اپنے نوکر کو بدی کے
رستہ پر گامزن پائے تو اس کا فرض ہے کہ اپنے جائز اقتدار کے ذریعہ اس بدی کا سدباب
کرے اور زبان سے روکنے سے نصیحت کرنا یا حسب ضرورت مناسب تنبیہ کے ذریعہ روکنا
مراد ہے اور دل کے ذریعہ اصلاح کرنے سے محض خاموش رہ کر دل میں بر اماننا مراد نہیں
کیونکہ آنحضرت صلی ال ہی میں نے دل کے ذریعہ بدلنے یا روکنے “ کے الفاظ استعمال فرمائے ہیں
اور یہ غرض محض دل میں برا ماننے کے ذریعہ پوری نہیں ہو سکتی.پس دل کے ذریعہ روکنے
سے مراد دل کی دعا ہے جو اصلاح کا ایک تجربہ شدہ ذریعہ ہے اور آنحضرت صلی للی کم کا منشاء یہ
ہے کہ اگر ایک انسان کسی بدی کو نہ تو ہاتھ سے روک سکے اور نہ ہی زبان سے روکنے کی
طاقت رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ کم از کم دل کی دعا کے ذریعہ ہی اصلاح کی کوشش کرے اور
یہ جو آنحضرت صلی اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ دل کے ذریعہ روکنے کی کوشش کرنا سب سے کمزور
قسم کا ایمان ہے اس سے یہ مراد ہے کہ محض دل کی دعا پر اکتفا کرنا بہت کمزور قسم کی چیز
ہے.اصل مجاہد انسان وہی سمجھا جا سکتا ہے جو دل کی دعا کے ساتھ ساتھ خدا کی پیدا کردہ
Page 58
46
ظاہری تدابیر بھی اختیار کرتا ہے جو شخص محض دعا پر اکتفا کرتا ہے اور بدی کو روکنے کے
لئے کوئی ظاہری تدبیر عمل میں نہیں لاتا وہ دراصل اصلاح نفس کے فلسفہ کو بہت کم سمجھا
ہے.دعا میں بے شک بڑی طاقت ہے لیکن زیادہ مؤثر دعاوہ ہے جس کے ساتھ ظاہری تدبیر
بھی شامل ہو تا کہ انسان نہ صرف اپنے قول سے بلکہ اپنے عمل کے ذریعہ بھی خدا کے فضل کا
جاذب بن سکے.پس تمام سچے مسلمانوں کو چاہیے کہ آنحضرت صلی ایم کے اس مبارک ارشاد پر
عمل کریں یعنی اگر ان کے سامنے کوئی ایسا شخص بدی کا مرتکب ہو جو ان کا کوئی عزیز یا
دوست یا ما تحت ہے تو اسے اپنے ہاتھ سے روک دیں اور اگر کوئی ایسا شخص بدی کا مرتکب
ہونے لگے جسے ہاتھ سے روکنا ان کے اختیار میں نہیں بلکہ ہاتھ کے ذریعہ روکنا فتنہ کا موجب
ہو سکتا ہے تو اسے زبان کی نصیحت سے روکنے کی کوشش کریں لیکن اگر اپنی کمزوری یا فتنہ
کے خوف کی وجہ سے انہیں ان دونوں باتوں کی طاقت نہ ہو تو پھر کم از کم اس بدی کے
استیصال کے لئے دل میں ہی سچی تڑپ کے ساتھ دعا کریں.افراد اور خاندانوں اور قوموں
کی اصلاح کے لئے یہ تدبیر اتنی مفید اور اتنی مؤثر اور اتنی بابرکت ہے کہ اگر مسلمان اس پر
عمل کریں تو ایک بہت قلیل عرصہ میں ملک کی کایا پلٹ سکتی ہے لیکن بدی کے نظاروں کو
تماشے کے رنگ میں دیکھنے والا انسان ہر گز سچا مسلمان نہیں سمجھا جا سکتا.
Page 59
47
9
جو بات اپنے لئے پسند کرتے ہو وہی
اپنے بھائی کے لئے پسند کرو
عنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ
لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ
(صحيح البخاري كتاب الايمان، باب من الايمان ان يحب لاخيه ما يحب لنفسه)
ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی علی کرم فرماتے تھے
کہ مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ تم میں سے کوئی شخص سچا
مومن نہیں سمجھا جا سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لئے وہی بات پسند نہیں کر تاجو وہ اپنے
لئے پسند کرتا ہے.تشریح: یہ حدیث اسلامی اخوت کا حقیقی معیار پیش کرتی ہے.سب سے پہلے قرآن
شریف نے تمام مسلمانوں کو انّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ( یعنی تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی
ہیں) کہہ کر بھائی بھائی بنایا اور اس کے بعد ہمارے آقا صلی الی مریم نے وہ الفاظ فرما کر جو اس حدیث
1 : الحجرات: 11
Page 60
48
میں بیان ہوئے ہیں اس اخوت کے بلند معیار کی وضاحت فرمائی.آپ فرماتے ہیں اور کس شان
کے ساتھ خدا کی قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ مومنوں کی اخوت کا حقیقی معیار یہ ہے کہ جو بات
ایک مسلمان اپنے لئے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لئے بھی پسند کرے.ان مختصر الفاظ
کے ذریعہ آپ نے گویا مسلمانوں میں ہر قسم کی دوئی اور غیریت کی جڑھ کاٹ کر انہیں بالکل
ایک جان کر دیا ہے مگر افسوس ہے کہ آج کل اکثر لوگ نفسا نفسی کی مرض میں مقبلا ہو کر اپنے
واسطے ہر خیر کو جمع کرنے اور دوسروں کو ہر خیر سے محروم کرنے کے درپے رہتے ہیں اور یہی وہ
لوگ ہیں جن کے متعلق قرآن شریف فرماتا ہے کہ
وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا
كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُوْلَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ
یعنی دوسروں کا حق مارنے والے لوگوں پر افسوس ہے کہ جب وہ دوسروں سے اپنا
حق وصول کرتے ہیں تو خوب بڑھا چڑھا کر لیتے ہیں لیکن جب خود دوسروں کا حق دینے لگتے ہیں
تو اپنا ناپ کم کر دیتے ہیں ؟ کیا یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ وہ خدا کے سامنے کبھی پیش نہیں کئے
جائیں گے ؟“
اسلام اس نفسا نفسی کی مرض کو جڑھ سے کاٹ کر حکم دیتا ہے کہ سچے مسلمانوں کا
فرض ہے کہ وہ جو کچھ اپنے لئے پسند کرتے ہیں وہی اپنے بھائی کے لئے بھی پسند کریں.1 : المطففين: 2 تا 5
Page 61
49
مگر اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ جو خاص حقوق شریعت نے قریبی رشتہ داروں
کے لئے مقرر کر دیئے ہیں انہیں ترک کر دیا جائے مثلاً باپ کا فرض ہے کہ چھوٹی عمر کی اولاد
کے اخراجات کا کفیل ہو.خاوند کا فرض ہے کہ بیوی کے اخراجات کو برداشت کرے.بچوں کا
فرض ہے کہ بوڑھے یا بے سہارا والدین کا بوجھ اٹھائیں.اسی طرح شریعت نے ایک شخص کے
مرنے پر اس کے ورثاء کے حصے بھی مقرر کر دیئے ہیں کہ بیوی کو اتنا حصہ ملے گا اور اولاد کو اتنا
حصہ ملے اور ماں باپ کو اتنا حصہ ملے وغیرہ وغیرہ اور دوسرے رشتہ داروں اور ہمسایوں اور
دوستوں کا خاص خیال رکھنے کی بھی تاکید فرمائی ہے.پس یہ مقررہ حقوق تو بہر حال مقدم رہیں
گے لیکن انہیں چھوڑ کر عام تعلقات اور معاملات میں اسلام ہر مسلمان سے توقع رکھتا اور اسے
تاکیدی ہدایت دیتا ہے کہ جو بات وہ اپنے لئے پسند کرتا ہے وہی اپنے مسلمان بھائی کے لئے
بھی پسند کرے اور یہ نہ ہو کہ اپنے لئے تو اس کا پیمانہ اور ہو اور دوسروں کے لئے اور ہو.ایک
دوسری حدیث میں ہمارے آقا صلی علی کرم فرماتے ہیں کہ تمام مسلمان آپس میں ایک انسانی جسم
کے اعضاء کا رنگ رکھتے ہیں جس طرح جسم کے ایک عضو کے دکھنے سے سارا جسم درد میں مبتلا
ہو جاتا ہے اسی طرح ایک مسلمان کے دکھ سے ساری قوم میں بے کلی اور بے چینی پید ا ہو جانی
چاہیے.یہ وہ اخوت کا بلند معیار ہے جس پر خدا کا رسول (فداہ نفسی) ہمیں لے جانا چاہتا
ہے.کاش ہم اس تعلیم کی قدر کریں.
Page 62
50
10
بھائی خواہ ظالم ہو یا مظلوم اس کی مدد کرو
عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْصُرُ
أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا تَنْصُرُهُ مَظْلُومًا فَكَيْفَ
تنْصُرُهُ ظَالِمًا قَالَ: تَأْخُذُ فَوْقَ يَدَيْهِ
(صحیح البخار المظالم ، باب اعن اخاک ظالما او مظلوما)
ترجمہ: انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی الیکم فرماتے تھے کہ اپنے مسلمان
بھائی کی بہر حال امداد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا کہ مظلوم ہو.صحابہ نے عرض کیا.یارسول اللہ ! مظلوم
بھائی کی مدد کا مطلب تو ہم سمجھ گئے مگر ظالم بھائی کی مدد کس طرح کی جائے ؟ آپ نے فرمایا.ظالم
بھائی کی مدد اس کے ظلم کے ہاتھ کو روک کر کرو.تشریح یہ لطیف حدیث فلسفہ اخوت اور فلسفہ اخلاق کا ایک نہایت گراں قدر
:
مجموعہ ہے.فلسفہ اخوت کا پہلو تو یہ ہے کہ ایک مسلمان بھائی کی مد دہر حال میں ہونی چاہیے خواہ
وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو.اخوت وہ چیز نہیں جسے کسی حالت میں بھی فراموش یا نظر انداز کیا
جائے.جو شخص ہمارا بھائی ہے وہ ہر صورت میں ہماری مدد کا مستحق ہے اور اس کا ظالم یا مظلوم
Page 63
51
ہونا اس کے اس حق پر کسی طرح اثر انداز نہیں ہو سکتا.اس کے مقابل پر اس حدیث کے فلسفہ
اخلاق کا پہلو یہ ہے کہ خواہ ہمارا واسطہ غیر کے ساتھ ہو یا کہ بھائی کے ساتھ ہمارا ہر حال میں
فرض ہے کہ دنیا سے ظلم اور بدی کو مٹائیں اور نیکی اور انصاف کو قائم کریں.کسی کے غیر
ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس پر ظلم کریں اور کسی کے بھائی ہونے کے یہ معنی نہیں کہ ہم
ایک ظلم میں بھی اس کے معین و مدد گار ہوں.اب غور کرو کہ بظاہر یہ دونوں باتیں ایک دوسرے سے کس قدر مخالف اور کتنی متضاد
نظر آتی ہیں.اگر ظالم بھائی کی مدد نہ کی جائے تو اخوت کی تاریں ٹوٹتی ہیں اور اگر ظالم بھائی کی
مدد کی جائے تو انصاف ہاتھ سے دینا پڑتا ہے لیکن ہمارے آقا (فداہ نفسی) نے ان متوازی
نہروں کو جو بظاہر ہمیشہ ایک دوسرے سے جدا ر ہتی ہوئی نظر آتی ہیں حکمت و دانش مندی کی
ایک درمیانی نہر کے ذریعہ اس طرح ملا دیا ہے کہ وہ گویا ایک جان ہو کر بہنے لگ گئی ہیں.فرماتے ہیں کہ اخوت ایک ایسا مقدس رشتہ ہے جو کسی حالت میں ٹوٹنا نہیں چاہیے.میر ابھائی
خواہ اچھا ہے یا برا، نیک ہے یابد ، ظالم ہے یا مظلوم بہر حال وہ میر ابھائی ہے اور اس کی اخوت کی
تاریں کسی حالت میں کائی نہیں جاسکتیں لیکن خدائے اسلام ظلم کی بھی اجازت نہیں دیتا اور
دشمن تک سے انصاف کا حکم فرماتا ہے اس لئے ان دو باتوں کو اس طرح ملاؤ کہ بھائی کی تو
بہر حال مدد کرو لیکن اس کے ظالم ہونے کی حالت میں اپنی مدد کی صورت کو بدل دو.اگر وہ
مظلوم ہے تو اس کے ساتھ ہو کر ظالم کا مقابلہ کرو اور اگر وہ ظالم ہے تو اس کے ساتھ لپٹ کر
اس کے ظلم کے ہاتھ کو مضبوطی کے ساتھ رو کو اور اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اس سے عرض کرو
Page 64
52
کہ بھائی ہر حال میں میں تمہارے ساتھ ہوں مگر اسلام ظلم کی اجازت نہیں دیتا اس لئے میں
تمہارے ہاتھ کو ظلم کی طرف بڑھنے نہیں دوں گا.یہ وہ مقدس اصول ہے جو اس لطیف
حدیث میں آنحضرت صلی ا یکم نے قائم فرمایا ہے.یہ خیال کرنا جیسا کہ بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ اس حدیث میں رسول اللہ صلی الل ولم
نے محض زور دینے کی خاطر خاص قسم کے الفاظ استعمال فرمائے ہیں ورنہ مقصد یہی ہے کہ اگر
تمہارا بھائی مظلوم ہے تو اس کی مدد کرو اور اگر وہ ظالم ہے تو اس کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، بالکل
غلط اور حدیث کے حکیمانہ الفاظ کے ساتھ گویا کھیلنے کے مترادف ہے.اگر آنحضرت صلی للی کم کا
یہی منشاء ہو تا تو آپ بڑی آسانی کے ساتھ فرما سکتے تھے کہ تم بہر حال ظلم کا مقابلہ کرو خواہ وہ
تمہارے دشمن کی طرف سے ہو یا تمہارے بھائی کی طرف سے لیکن آپ نے ہر گز ایسا نہیں
فرمایا بلکہ آپ نے اس فرمان میں بظاہر دو متضاد باتوں کو ملا کر ایک نہایت لطیف اور اچھوتا
نظر یہ قائم فرمایا ہے جو یہ ہے کہ
(i) بھائی بہر حال مدد کا مستحق ہے.(ii) ظلم کا بہر حال مقابلہ ہو نا چاہیے.(iii) اگر بھائی مظلوم ہو تو اس کی مدد کرو اور اگر بھائی ظالم ہو تو مدد کی نوعیت کو
بدل کر اس کے ظلم کے ہاتھ کو روکو تاکہ اخوت بھی قائم رہے اور ظلم کا انسداد بھی
ہو جائے.
Page 65
53
یہ وہ مرکب نظریہ ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے چودہ سو سال
پیشتر عرب کے صحر اسے اٹھ کر دنیا کے سامنے پیش کیا لیکن آج تک یورپ اور امریکہ کی کوئی
ترقی یافتہ قوم بھی اس نظریہ کی بلندی کو نہیں پہنچ سکی.انہوں نے اگر کسی قوم کے ساتھ اخوت
کا عہد باندھا تو اس اخوت کے اکرام میں بے پناہ ظلم کا دروازہ کھول دیا اور اگر بزعم خود کسی ظلم
کے انسداد کے لئے اٹھے تو اخوت کے عہد کی دھجیاں اڑا دیں.
Page 66
54
11
اسلام میں اطاعت کا بلند معیار
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ السَّبْعُ وَ
الطاعَةُ عَلَى المَرْءِ المُسْلِمِ فِيهَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَالَهُ يُؤْمَرُ مَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ
بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَة
(صحيح البخاري كتاب الاحكام باب السمع والطاعة للامام مالم تكن معصية )
ترجمہ: عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ہر مسلمان پر اپنے افسروں کی ہر بات سننا اور ماننا فرض
ہے خواہ اسے ان کا کوئی حکم اچھا لگے یا برا لگے سوائے اس کے کہ وہ کسی ایسی بات کا حکم دیں
جس میں خدا اور رسول کے کسی حکم کی یا کسی بالا افسر کے حکم کی نافرمانی لازم آتی ہو.اگر وہ
ایسی نافرمانی کا حکم دیں تو پھر اس میں ان کی اطاعت فرض نہیں.تشریح: یہ حدیث اسلامی معیار اطاعت کا بنیادی اصول پیش کرتی ہے اسلام ایک
انتہا درجہ کا نظم و ضبط والا مذہب ہے.وہ کسی شخص کو اپنے حلقہ میں جبر أداخل کرنے کا موید
Page 67
55
نہیں اور صاف اعلان کرتا ہے کہ لا إكراه في الدين (یعنی دین کے معاملہ میں کوئی جبر
نہیں) لیکن جب کوئی شخص خوشی اور شرح صدر کے ساتھ اسلام قبول کرتا ہے تو پھر اسلام
اس سے اس نظم و ضبط کی توقع رکھتا ہے جو ایک منظم قوم کے شایان شان ہے.وہ اپنے ہر فرد کو
کامل اطاعت کا نمونہ بنانا چاہتا ہے اور افسروں کے حکموں پر حیل و حجت کی اجازت نہیں دیتا کہ
جو حکم پسند ہو اوہ مان لیا اور جو نا پسند ہوا اس کا انکار کر دیا.”سنو اور مانو “ اسلام کا ازلی نعرہ رہا
ہے.مسلمان کے اس ضابطہ اطاعت میں صرف ایک ہی استثناء ہے اور وہ یہ کہ اسے کسی ایسی
بات کا حکم دیا جائے جو صریح طور پر خدا اور اس کے رسول یا کسی بالا افسر کے حکم کے خلاف
ہو.اس کے علاوہ ہر حکم میں خواہ وہ کچھ ہو اور کیسے ہی حالات میں دیا جائے ”سنو اور مانو کا اٹل
قانون چلتا ہے.اور یہ جو اس حدیث میں الطاعة (یعنی مانو) کے لفظ کے ساتھ السّبُعُ (یعنی سنو)
کے لفظ کا اضافہ کیا گیا ہے اس میں اس لطیف حکمت کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ ایک
مسلمان کا کام صرف منفی قسم کی اطاعت نہیں ہے کہ جو حکم اسے پہنچ جائے وہ اسے مان لے اور
بس بلکہ اسے مثبت قسم کی شوق آمیز اطاعت کا نمونہ دکھانا چاہیے اور گویا اپنے افسروں کی
طرف کان لگائے رکھنا چاہیے کہ کب ان کے منہ سے کوئی بات نکلے اور کب میں اسے مانوں
ور نہ محض اطاعت کے لئے الطاعة (یعنی مانو) کا لفظ بولنا کافی تھا اور السبع ( یعنی سنو) کا
لفظ زیادہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی.اس لفظ کا زیادہ کرنا یقینا اسی غرض سے ہے کہ تا
1 : البقرة: 257
Page 68
56
رسمی اطاعت کی بجائے شوق آمیز اطاعت کا معیار قائم کیا جائے.پس اسلامی ضابطہ اطاعت کا
خلاصہ یہ ہے کہ
نا پسند ہو.(۱) ہر امر میں اپنے افسر کے حکم کی اطاعت کرو خواہ اس کا کوئی حکم تمہیں پسند ہو یا
(۲) اپنے افسر کی طرف شوق کے ساتھ کان لگائے رکھو تا کہ اس کا کوئی حکم تمہاری تعمیل
سے باہر نہ رہ جائے.(۳) لیکن اگر تمہارا افسر کسی ایسی بات کا حکم دے جو خد اتعالیٰ اور اس کے رسول یا
کسی بالا افسر کے حکم کے صریح خلاف ہے تو پھر جہاں تک اس حکم کا تعلق ہے اس کی اطاعت نہ
کرو.
Page 69
57
12
ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا
سامنے
افضل ترین جہاد ہے
عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ وَضَعَ رِجْلَهُ
في العزيز ألى الجهاد أفضَلُ قَالَ: كَلِمَةُ على عِندَ سُلطان جائر.(سنن النسائي كتاب البيعة، فضل من تكلم بالحق عند امام جائر
سة
ترجمہ : طارق بن شہاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک شخص نے
ایسے وقت میں رسول اللہ صلی العلیم سے سوال کیا جب آپ ایک سفر پر جاتے ہوئے اپنی رکاب
میں پاؤں ڈال رہے تھے اس نے پوچھا.یارسول اللہ ! کون سا جہاد افضل ہے ؟ آپ نے فرمایا.انصاف کے رستے سے بھٹکے ہوئے بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا.“
تشریح: اگر ایک طرف اسلام نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنے امیر یا حاکم
کی اطاعت کا اعلیٰ نمونہ دکھائیں اور اس کے احکام کو توجہ سے سنیں اور شرح صدر سے بجالائیں
تو دوسری طرف اس نے ماتحتوں کا بھی یہ فرض مقرر کیا ہے کہ اگر ان
کا بادشاہ یا امیر یا حاکم
Page 70
58
(کیونکہ اس جگہ سلطان کے مفہوم میں یہ سب لوگ شامل ہیں) انصاف کے رستہ سے بھٹکنے
لگے اور ظلم کا طریق اختیار کرے تو وہ اخلاقی جرات سے کام لے کر اسے نیک مشورہ دیں اور
حاکم کے رویہ میں اصلاح کی کوشش کر کے ملک میں عدل و انصاف کو قائم کرنے میں مدد دیں
اور چونکہ جائز اور غصہ میں آئے ہوئے حاکم کو نیکی کا مشورہ دینا غیر معمولی جرآت چاہتا ہے اور
بعض اوقات خطرہ سے بھی خالی نہیں ہوتا اس لئے آنحضرت صلی اللہ تم نے اس کوشش کو افضل
جہاد کے نام سے موسوم کیا ہے.حق یہ ہے کہ اسلام نے حاکم اور محکوم اور راعی اور رعیت کے حقوق میں ایسا لطیف
توازن قائم کیا ہے کہ اس معاملہ میں اس سے بڑھ کر کوئی اور تعلیم خیال میں نہیں آسکتی.سب
سے اوّل نمبر پر اسلام نے بلا امتیاز قوم و ملت یہ ہدایت دی ہے کہ حکومت کے تمام عہدے
(جس میں حاکم اعلیٰ سے لے کر سب سے نیچے کا افسر بھی شامل ہے) صرف اہلیت کی بناء پر
تقسیم ہونے چاہیں.چنانچہ قرآن شریف میں آتا ہے.إنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمُ
انْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
1 : النساء: 59
Page 71
59
یعنی حکومت کے تمام عہدے ایک مقدس امانت ہیں اور اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا
ہے کہ یہ امانت صرف اہلیت رکھنے والے لوگوں کے سپر د کیا کرو اور پھر جو لوگ حاکم مقرر
ہوں ان کا فرض ہے کہ کامل عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کریں.“
اس کے بعد دوسرے نمبر پر اسلام یہ ہدایت دیتا ہے کہ لوگوں کا فرض ہے کہ اپنے
حاکموں کی پوری پوری اطاعت کریں اور ان کے احکام کو توجہ کے ساتھ سنیں اور شوق کے
ساتھ بجالائیں.اور پھر تیسرے نمبر پر اسلام یہ ہدایت فرماتا ہے کہ اگر کوئی حاکم انصاف کے رستہ
سے ہٹنے لگے تو ماتحتوں کا فرض ہے کہ بروقت نیک مشورہ دے کر اس کی اصلاح کی کوشش
کریں کیونکہ ملکی امن کے لحاظ سے یہ مشورہ ایک اعلیٰ قسم کے جہاد سے کم نہیں لیکن چونکہ بعض
ماتحت لوگ اس معاملہ میں خود داری یا جلد بازی یا ناواجب رقابت یا ذاتی رنجش کے طریق پر
غلط قدم اٹھا سکتے ہیں اس لئے جیسا کہ خدا تعالیٰ فرعون کے معاملہ میں حضرت موسیٰ کو فَقُولا
لَهُ قَوْلًا لينا (یعنی فرعون کے ساتھ نرم انداز میں بات کرنا) کے الفاظ میں ہدایت فرماتا
ہے.اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ ایسے امور میں کوئی خلاف آداب طریق یا گستاخی کا انداز یا بغاوت
کارنگ اختیار نہیں کرنا چاہیے بلکہ جیسا کہ ایک دوسری حدیث میں صراحت آئی ہے اگر بعض
مظالم بر داشت کر کے بھی صبر سے کام لیا جا سکے تو وہ بہتر ہے تا کہ ملک کا امن اور قوم کا اتحاد
خطرہ میں نہ پڑے اور یہی وہ وسطی تعلیم ہے جو دنیا میں حقیقی امن کی بنیاد بن سکتی ہے.45:16:1
Page 72
60
60
لیکن افسوس یہ ہے کہ حاکموں کو نیک مشورہ دینے اور انہیں عدل و انصاف کے مقام
پر قائم رکھنے کی بجائے آج کل اکثر لوگ افسروں کو بگاڑنے کا طریق اختیار کرتے ہیں اور ایک
طرف جھوٹی خوشامد کے ذریعہ اور دوسری طرف رشوت کے ناپاک وسیلہ سے حاکموں کے
اخلاق اور ان کے جذبہ انصاف کو تباہ کرنے کے درپے رہتے ہیں.حالانکہ آنحضرت
صلى الم نے رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے دونوں پر لعنت بھیجی ہے اور ایک دوسری
حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ
الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي فِي النَّارِ
یعنی رشوت دینے والا شخص اور رشوت لینے والا شخص دونوں آگ کا ایندھن ہیں،
کاش اسلامی ممالک تو اس لعنت سے آزاد ہو سکیں.1 : كنز العمال، تابع حرف الحاء ، كتاب الامارة والقضاء ، باب الثانى فى القضاء ، الفصل الثالث في الهداية والرشوة، باب
الرشوة ، روايت نمبر 15077)
Page 73
61
13
چھوٹوں پر رحم کرو
اور بڑوں کے حق کو پہچانو
عن عبد الله بن عمر و...عن النبي صلى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَمْ يركم
صَغِيرَنَا، وَيَعْرِفُ حَقَ كَبِيرِ نَا فَلَيْسَ مِنَّا.(سنن أبي داود كتاب الادب، باب فى الرحمة)
ترجمہ : عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی العلیم فرماتے
تھے کہ جو شخص ہم میں سے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور ہم میں سے بڑوں کا حق نہیں پہچانتا
اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں.تشریح: اس حدیث میں باہمی تعلقات کا ایک لطیف گر بیان کیا گیا ہے.دنیا میں اکثر
فسادات اور جھگڑے اس لئے ہوتے ہیں کہ بڑے لوگ چھوٹوں کے ساتھ شفقت اور رحم کا
سلوک نہیں کرتے اور چھوٹے لوگ بڑوں کے واجبی احترام سے غافل رہتے ہیں اور اس طرح
ایک ناگوار طبقاتی کش مکش کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے.اسلام نے ایک طرف تو سرکاری
Page 74
62
عہدوں اور دولت پیدا کرنے کے ذرائع کے حصول میں سب کے واسطے برابر کے حقوق تسلیم
کئے اور دوسری طرف سوسائٹی کے مختلف طبقات میں ایک طرف سے شفقت و رحمت اور
دوسری طرف سے ادب و احترام کا مضبوط پل باندھ کر سب کو ایک لڑی میں پرو دیا.جن
لوگوں کو زندگی کی جدوجہد میں دوسروں سے آگے نکلنے کا موقع میسر آجاتا ہے ان کے لئے حکم
ہے کہ وہ پیچھے رہنے والوں کے ساتھ جب تک کہ وہ پیچھے ہیں شفقت ورحم کا سلوک کریں اور
جو لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں ان کے لئے یہ حکم ہے کہ وہ آگے نکل جانے والوں کے ساتھ جب
تک کہ وہ آگے ہیں واجبی ادب و احترام سے پیش آئیں.اس زریں ہدایت کے ذریعہ ہمارے
آقا صلی الم نے سوسائٹی کے مختلف طبقات کے درمیان ناواجب کشمکش کی جڑھ کاٹ کر رکھ دی
ہے مگر افسوس ہے کہ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اس تعلیم پر عمل کرتے ہیں.اگر کسی شخص کو
کسی وجہ سے کوئی طاقت حاصل ہو جاتی ہے تو وہ تکبر میں مبتلا ہو کر اپنے سے نیچے کے لوگوں کو
کچل دینے کا متمنی ہوتا ہے اور اگر کوئی شخص زندگی کی دوڑ میں کسی وجہ سے پیچھے رہ جاتا ہے تو وہ
حسد میں جل کر آگے نکل جانے والوں کو نیچے گرانے اور تباہ کرنے کے درپے ہو جاتا ہے.یہ
دونوں قسم کے لوگ اسلام کی منصفانہ تعلیم سے کوسوں دور ہیں.اسلام یقیناً طبقات پیدا نہیں کرتا مگر جو وقتی امتیاز افراد کے دماغی قوی یا ذاتی جد وجہد
کے فرق کی وجہ سے خود بخود طبعی رنگ میں پیدا ہو جاتا ہے وہ جب تک اسی قسم کے طبعی طریق
پر دور نہ ہو اسلام اس کی طرف سے آنکھیں بند کر کے حقائق کو نظر انداز بھی نہیں کرتا بلکہ
اسے اپنے نوٹس میں لاکر اس کے ناگوار نتائج کو روکنے کے لئے مناسب تدابیر اختیار کر تا ہے
Page 75
63
اور آنحضرت صلی علی یم کا یہ مبارک ارشاد انہی تدابیر کا حصہ ہے اور اس کے ساتھ اسلام اس
بات پر بھی زور دیتا چلا جاتا ہے کہ اس قسم کے امتیازات محض عارضی ہو ا کرتے ہیں اور آج جو
طبقہ نیچے ہے کل کو وہ ترقی کر کے اوپر آسکتا ہے.چنانچہ قرآن شریف فرماتا ہے:
لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ
د یعنی سوسائٹی کے کسی طبقہ کے لئے جائز نہیں کہ وہ کسی دوسرے طبقہ کو ادنی خیال
کر کے اسے تحقیر کی نظر سے دیکھے کیونکہ جو طبقہ نیچے ہے کل کو وہی طبقہ اوپر آکر تحقیر کرنے
والوں سے بہتر بن سکتا ہے.“
یہ بھی یادرکھنا چاہیے کہ اس حدیث میں جو صغیر اور کبیر کا لفظ آتا ہے اس سے عربی
محاورہ کے مطابق ہر قسم کے چھوٹے بڑے مراد ہیں.خواہ یہ فرق اثر ورسوخ کے لحاظ سے ہویا
افسری ماتحتی کے لحاظ سے ہو یا دولت کے لحاظ سے یا رشتہ کے لحاظ سے ہو یا عمر کے لحاظ سے ہو.بہر حال جس جہت سے بھی فرق ہو گا ہر بڑے کے لئے یہ حکم ہے کہ وہ اپنے سے چھوٹے کے
ساتھ شفقت و محبت کا سلوک کرے اور ہر چھوٹے کے لئے یہ حکم ہے کہ وہ اپنے سے بڑے
کے ساتھ واجبی ادب و احترام سے پیش آئے اور جو شخص ایسا نہیں کرتا اس کے متعلق ہمارے
66
آقا آنحضرت صلی الله علم فرماتے ہیں کہ لیس منا ”وہ ہم میں سے نہیں.“
الحجرات : 12
Page 76
64
14
شرک اور والدین کی نافرمانی اور جھوٹ
سب سے بڑے گناہ ہیں
عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن أَبي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ رَين اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبي صَلَّى
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا قَالُوا : بَلَى يَا رَسُولَ الله
قَالَ الإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ - وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِنًا فَقَالَ - أَلَا
وَقَوْلُ النُّورِ، قَالَ فَمَازَالَ يُكَرِرُهَا حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ
(صحيح البخاري كتاب الشهادات باب ما قيل في شهادة الزور)
ترجمہ: ابو بکرۃ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول
اللہ صلی الم نے فرمایا کہ اے لوگو !
میں تمہیں سب سے بڑے گناہوں پر مطلع نہ کروں ؟ اور (صحابہ کو متوجہ کرنے کے لئے ) آپ
نے یہ الفاظ تین دفعہ دہرائے.صحابہ نے عرض کیا.ہاں رسول اللہ.آپ ضرور ہمیں مطلع
فرمائیں.آپ نے فرمایا تو پھر سنو کہ سب سے بڑا گناہ خدا تعالیٰ کا شرک ہے اور پھر دوسرے
نمبر پر سب سے بڑا گناہ والدین کی نافرمانی اور ان کی خدمت کی طرف سے غفلت برتنا ہے اور
پھر...اور یہ بات کہتے ہوئے آپ تکیے کا سہارا چھوڑ کر جوش کے ساتھ بیٹھ گئے اور پھر فرمایا...
Page 77
55
65
اچھی طرح سن لو کہ اس کے بعد سب سے بڑا گناہ جھوٹ بولنا ہے اور آپ نے اپنے ان آخری
الفاظ کو اتنی دفعہ دہرایا کہ ہم نے آپ کی تکلیف کا خیال کرتے ہوئے دل میں کہا کہ کاش اب
آپ خاموش ہو جائیں اور اتنی تکلیف نہ اٹھائیں.تشریح : اس زور دار حدیث میں آنحضرت صلی ا ہم نے سب سے بڑے گناہوں کا ذکر
فرماتے ہوئے تین ایسی باتوں کو چنا ہے جو روحانیات اور اخلاقیات کے تین مختلف میدانوں کی
بنیادی باتیں ہیں.یہ تین میدان (۱) حقوق اللہ (۲) حقوق العباد اور (۳) اصلاح نفس کے
ساتھ تعلق رکھتے ہیں.سب سے بڑا گناہ شرک ہے یعنی خدا کے مقابل پر جو ہمارا خالق بھی ہے
اور مالک بھی ہے کسی ایسی ہستی کو کھڑا کرنا جو نہ تو ہمارا خالق ہے اور نہ مالک.اس لئے شرک کا
گناہ دراصل غداری اور بغاوت دونوں کا مجموعہ ہے یہ انتہا درجہ کی غداری ہے کہ جس ہستی نے
ہمیں پیدا کیا اور ہماری دینی اور دنیوی ترقی کے اسباب مہیا کئے اس کے مقابل پر ایسی ہستیوں
کے ساتھ تعلق قائم کیا جائے جن کا نہ تو ہماری پیدائش کے ساتھ کوئی تعلق ہے اور نہ ہماری بقا
کے ساتھ ان کا کوئی واسطہ ہے اور پھر یہ انتہا درجہ کی بغاوت بھی ہے کہ دنیا کے حقیقی مالک اور
حقیقی حکمران کی حکومت سے سرتابی کر کے ایسی ہستیوں کے سامنے سر جھکایا جائے جنہیں ہم
پر کسی نوع کا ذاتی تصرف حاصل نہیں لیکن افسوس ہے کہ آج کل ترقی یافتہ دنیا میں بھی ایسی
قو میں پائی جاتی ہیں جن کا دامن ان کی بظاہر اعلیٰ تعلیم اور اعلیٰ تہذیب کے باوجود شرک کی
نجاست سے پاک نہیں چنانچہ عیسائی اقوام حضرت مسیح ناصری کو (جن میں دوسرے نبیوں سے
Page 78
66
ہر گز کوئی زائد بات نہیں تھی) خدا مان کر اب تک شرک کی دلدل میں پھنسی ہوئی ہیں اور
ہندوؤں کے ہزاروں دیو تا تو ایک کھلی ہوئی کہانی کا حصہ ہیں جسے بچہ بچہ جانتا ہے.دوسر ا بڑا گناہ اس حدیث میں عقوق الوالدین بیان کیا گیا ہے.عقوق کے معنی عربی
زبان میں کسی چیز کو کاٹنے کے ہیں اور اصطلاحی طور پر اس کے معنی ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ان
کا واجبی ادب ملحوظ نہ رکھنا، ان کے ساتھ شفقت سے پیش نہ آنا اور انکی خدمت سے غفلت برتنا
ہے.والدین کی اطاعت اور خدمت کا فریضہ حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہے اور دنیا کے حقوق
میں غالباً سب سے زیادہ مقدس حق قرار دیا گیا ہے حتی کہ ایک دوسری حدیث میں آنحضرت
لی یہ کم فرماتے ہیں کہ ماں باپ کی خوشی میں خدا کی خوشی ہے اور ماں باپ کی ناراضگی میں خدا کی
ناراضگی ہے اور ایک اور حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اپنے والدین کے
بڑھاپے کا زمانہ پایا اور پھر اس نے ان کی خدمت کے ذریعہ اپنے واسطے جنت کا رستہ نہیں کھولا،
وہ بڑا ہی بد قسمت انسان ہے اور آپ کا ذاتی اسوہ اس معاملہ میں یہ ہے کہ جب ایک دفعہ آپ
کچھ مال تقسیم فرمانے میں مصروف تھے تو آپ کی رضاعی والدہ آپ کے ملنے کے لئے آئیں
آپ کی حقیقی والدہ آپ کے بچپن میں ہی فوت ہو گئی تھیں) آپ انہیں دیکھتے ہی میری ماں
میری ماں کہتے ہوئے ان کی طرف لپکے.ان کے لئے اپنی چادر بچھا کر انہیں بڑی محبت اور
1
: معجم الكبير للطبراني، باب عبد اللہ بن عمر و بن العاص الله
2 : صحیح مسلم کتاب البر والصلة ، باب ،غم من اردک ابویه او احدهما.
Page 79
67
عزت کے ساتھ بٹھایا.الغرض اسلام نے والدین کی اطاعت اور خدمت کے متعلق انتہائی
تاکید فرمائی ہے حتی کہ قرآن شریف فرماتا ہے.وَاخْفِضُ لَهُمَا جَنَاحَ اللَّهِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ
ربِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّينِي صَغِيرًا 2
یعنی تم اپنے ماں باپ کے سامنے عاجزی اور انکساری کے بازوؤں کو محبت اور رحمت
کے ساتھ جھکائے رکھو اور ان کے لئے ہمیشہ خدا سے دعا مانگتے رہو کہ خدایا! جس طرح میرے
والدین نے مجھے بچپن میں جبکہ میں بالکل بے سہارا تھا محبت اور شفقت کے ساتھ پالا اسی طرح
اب تو ان کے بڑھاپے میں ان پر شفقت ورحم کی نظر رکھ.“
تیسر ابڑا گناہ اس حدیث میں جھوٹ بولنا بیان کیا گیا ہے اور اس کے متعلق اسلام کا
لمر یہ اس حدیث کے الفاظ سے ظاہر ہے کہ جب آپ جھوٹ کا ذکر فرمانے لگے تو جوش کے
ساتھ اٹھ کر بیٹھ گئے اور ان الفاظ کو بار بار دہرایا کہ أَلَا وَقَوْلُ الزُورٍ - أَلَا وَقَوْلُ النُّورِ یعنی
کان کھول کر سن لو.ہاں پھر کان کھول کر سن لو کہ شرک اور عقوق والدین کے بعد سب سے
بڑا گناہ جھوٹ بولنا ہے.“ حق یہ ہے کہ اگر باقی باتیں اس بیج کا حکم رکھتی ہیں جن سے گناہ کا
درخت پیدا ہو تا ہے تو جھوٹ اس پیج کے واسطے پانی کے طور پر ہے جس کی وجہ سے یہ درخت
پنپتا اور ترقی کرتا ہے.یہ جھوٹ ہی ہے جس کی وجہ سے گناہ پر دلیری پید اہوتی اور انسان گناہ
1
سنن ابو داؤد کتاب الادب، ابواب النوم ، باب في بر الوالدين
2 :بنی اسرائیل: 25
Page 80
68
کی دلدل میں پھنسے رہنے کا ایک بہانہ حاصل کر لیتا ہے کیونکہ جھوٹ کے ذریعہ گناہ پر پردہ ڈالا
جاتا ہے اور پھر اس پردہ کی اوٹ میں گناہ بڑھتا اور پھلتا چلا جاتا ہے.پس جھوٹ صرف اپنی
ذات میں ہی گناہ نہیں ہے بلکہ دوسرے گناہوں کے واسطے ایک بدترین قسم کا سہارا بھی ہے.اسی لئے آنحضرت صلی الی ایم نے جھوٹ کو شرک اور عقوق والدین کے بعد سب سے بڑا گناہ قرار
دیا ہے.ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ ایک مسلمان نے آپ سے عرض کیا.یا
رسول اللہ ! میرا نفس کمزور ہے اور میں بہت سی کمزوریوں میں مبتلا ہوں اور میں سارے
گناہوں کو یک دم چھوڑنے کی ہمت نہیں پاتا.آپ مجھے ہدایت فرمائیں کہ میں سب سے پہلے
کس گناہ کو چھوڑوں ؟ آپ نے فرمایا.”جھوٹ بولنا چھوڑ دو“.اس نے اس کا وعدہ کیا اور گھر
واپس آگیا.پھر جب وہ اپنی عادت کے مطابق بعض دوسرے گناہوں کا ارتکاب کرنے لگا تو
اسے خیال آیا کہ اب اگر رسول اللہ تک میری یہ بات پہنچی اور آپ نے مجھ سے پوچھا تو جھوٹ
تو بہر حال میں نے بولنا نہیں میں آپ کو کیا جواب دوں گا؟ یا اگر کسی مسلمان کو میری کسی
کمزوری کا علم ہوا تو اس کے سامنے میں اپنے اس گناہ پر کس طرح پردہ ڈالوں گا؟ آخر اسی میں
اس نے سوچتے سوچتے فیصلہ کیا کہ جب چھوڑ دیا ہے تو اب یہی بہتر ہے کہ سارے گناہوں سے
ہی اجتناب کیا جائے.چنانچہ وہ جھوٹ چھوڑنے کی برکت سے سب گناہوں سے نجات پا گیا.پس آنحضرت صلی ا ہم نے کمال حکمت سے جھوٹ کے گناہ کو شرک اور عقوق والدین کے
گناہوں کے بعد سب سے بڑا گناہ قرار دے کر مسلمانوں کی اصلاح کا ایک ایسا نفسیاتی نکتہ بیان
1 : ربيع الابرار، الباب الحادى و السبعون ، الكذب والزور.....روایت نمبر 2 ، جلد 4 ، صفحہ 339
Page 81
69
60
فرمایا ہے جس کے ذریعہ وہ بہت جلد اپنے گناہوں پر غلبہ پاسکتے ہیں.حق یہ ہے کہ جھوٹ ایک
بد ترین اور ذلیل ترین قسم کا گناہ ہے اور ہر شریف انسان کا فرض ہے کہ اخلاقی گناہوں میں
سب سے پہلے جھوٹ پر غلبہ پانے کی کوشش کرے.لیکن ضمنا یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ جھوٹ نہ بولنے کی تعلیم سے یہ مراد ہرگز
نہیں کہ ہر حال میں سچی بات بلا ضرورت بیان کر دی جائے بلکہ مراد صرف یہ ہے کہ جو بات
بیان کی جائے وہ بہر حال سچی اور جھوٹ کی آمیزش سے پاک ہونی چاہیے.ورنہ بسا اوقات
قومی یا خاندانی یا ذاتی مصالح بعض باتوں میں راز داری کے متقاضی ہوتے ہیں اور راز داری ہر گز
راست گفتاری کے خلاف نہیں.
Page 82
70
15
اولاد کا بھی اکرام کرو اور
انہیں بہترین تربیت دو
أَخْبَرَنِي الْحَارِثُ بْنُ النُّعْمَانِ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ عَنْ
رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَكْرِمُوا أَوْلَادَكُمْ وَأَحْسِنُوا أَدَبَهُمْ.(سنن ابن ماجه کتاب الادب باب بر الوالد والاحسان الى البنات)
ترجمہ : حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ
صلی ایم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ اپنی اولاد کی بھی عزت کیا کرو اور ان کی تربیت کو بہترین قالب
میں ڈھالنے کی کوشش کرو.تشریح: اسلام نے جہاں والدین کا حق اولاد پر تسلیم کیا ہے اور اولاد کو ماں باپ کی
عزت اور خدمت کی انتہائی تاکید فرمائی ہے وہاں والدین کو بھی حکم دیا ہے کہ وہ بھی اپنی اولاد کا
واجبی اکرام کریں اور ان کے ساتھ ایسا رویہ رکھیں جس سے ان کے اندر وقار اور عزت نفس کا
Page 83
71
جذبہ پید اہو اور پھر ان کی تعلیم و تربیت کی طرف بھی خاص توجہ دیں تاکہ وہ بڑے ہو کر حقوق
اللہ اور حقوق العباد کو بہترین صورت میں ادا کر سکیں اور ترقی کا موجب ہوں.حق یہ ہے کہ کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی بلکہ کوئی قوم تنزل سے بچ نہیں سکتی جب تک
کہ اس کے افراد اپنی اولاد کو اپنے سے بہتر حالت میں چھوڑ کر نہ جائیں.اگر ہر باپ اس بات کا
اہتمام کرے کہ وہ اپنی اولاد کو علم و عمل دونوں میں اپنے سے بہتر حالت میں چھوڑ کر جائے گا تو
یقینا قوم کا ہر اگلا قدم ہر پچھلے قدم سے اونچا اٹھے گا اور ایسی قوم خدا کے فضل سے تنزل کے
خطرات سے محفوظ رہے گی مگر افسوس ہے کہ اکثر والدین اس زریں اصول کو مد نظر نہیں
رکھتے جس کی وجہ سے کئی بچے ماں باپ سے بہتر ہونا تو در کنار ایسی حالت میں پرورش پاتے ہیں
کہ گویا ایک زندہ انسان کے گھر میں مردہ بچہ پیدا ہو گیا ہے.ایسے ماں باپ بچوں کے کھانے
پینے اور لباس وغیرہ کا تو خیال رکھتے ہیں اور کسی حد تک ان کی تعلیم کا بھی خیال رکھتے ہیں کیونکہ
وہ ان کی اقتصادی ترقی کا ذریعہ بنتی ہے مگر ان کی تربیت کی طرف سے عموماً ایسی غفلت برتتے
ہیں کہ گویا یہ کوئی قابل توجہ چیز ہی نہیں حالانکہ تربیت کا سوال تعلیم کی نسبت بہت زیادہ
ضروری اور تربیت کا مقام تعلیم کی نسبت بہت زیادہ بلند ہے.ایک کم تعلیم یافتہ مگر اچھے اخلاق
کا انسان جس میں محنت اور صداقت اور دیانت اور قربانی اور خوش خلقی کے اوصاف پائے
جائیں اس اعلی تعلیم یافتہ انسان سے یقینا بہتر ہے جس کے سر پر گدھے کی طرح علم کا بوجھ تو لدا
ہوا ہے مگر وہ اعلیٰ اخلاق سے عاری ہے اور قرآن شریف نے جو لَا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ
: بنی اسرائیل: 32
1
Page 84
72
( یعنی اپنی اولاد کو قتل نہ کرو) کے الفاظ فرمائے ہیں ان میں بھی اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرنا
مقصود ہے کہ اگر تم اپنے بچوں کی عمدہ تربیت اور اچھی تعلیم کا خیال نہیں رکھو گے تو تم گویا
انہیں قتل کرنے والے ٹھہر وگے.باقی رہا اس حدیث کا دوسرا حصہ یعنی اولاد کا اکرام کرنا.سو یہ بات وہ ہے جس میں
اسلام کے سوا کسی دوسری شریعت نے توجہ ہی نہیں دی کیونکہ دنیا کے کسی اور مذہب نے اس
نکتہ کو نہیں سمجھا کہ اولاد کے واجبی اکرام کے بغیر بچوں کے اندر اعلیٰ اخلاق پیدا نہیں کئے
جاسکتے.بعض نادان والدین بچوں کی محبت کے باوجود ان کے ساتھ بظاہر ایسا پست اور عامیانہ
سلوک کرتے اور گالی گلوچ سے کام لیتے ہیں کہ ان کے اندر و قار اور خود داری اور عزت نفس
کا جذبہ ٹھٹھر کر ختم ہو جاتا ہے.پس ہمارے آقا (فداہ نفسی) کی یہ تعلیم در حقیقت سنہری
حروف میں لکھنے کے قابل ہے کہ اپنی اولاد کے ساتھ بھی واجبی اکرام سے پیش آنا چاہیے تا ان
کے اندر باوقار انداز اور اعلیٰ اخلاق پیدا ہو سکیں.کاش ہم لوگ اس حکیمانہ تعلیم کی قدر
پہچانیں.☆☆☆
Page 85
73
16
بیوی کے انتخاب میں دینی پہلو کو مقدم کرو
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ
لأربع: لِمَالِهَا، وَلحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِيبينهَا فَاظُفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ.(صحیح مسلم کتاب الرضاع باب استحباب النكاح ذات الدين)
ترجمہ: ابوہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی ا ولم فرماتے تھے کہ
بیوی کے انتخاب میں عموماً چار باتیں مد نظر رکھی جاتی ہیں.بعض لوگ تو کسی عورت کے مال و
دولت کی وجہ سے اس کے ساتھ شادی کرنے کی خواہش کرتے ہیں اور بعض لوگ عورت کے
خاندان اور حسب و نسب کی وجہ سے شادی کے خواہاں ہوتے ہیں اور بعض لوگ عورت کے
حسن و جمال پر اپنے انتخاب کی بنیاد رکھتے ہیں اور بعض لوگ دین اور اخلاق کی وجہ سے بیوی کا
انتخاب کرتے ہیں.سواے مرد مسلم ! تو دیندار اور با اخلاق رفیقہ حیات چن کر اپنی زندگی کو
کامیاب بنانے کی کوشش کر ورنہ تیرے ہاتھ ہمیشہ خاک آلود رہیں گے.تشریح : اس حدیث میں آنحضرت صلی علیم نے یہ بتانے کے بعد کہ دنیا میں عام طور پر
بیوی کا انتخاب کن اصولوں پر کیا جاتا ہے مسلمانوں کو تاکید فرمائی ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے انتخاب
Page 86
74
میں دین اور اخلاق کے پہلو کو مقدم رکھا کریں.آپ فرماتے ہیں کہ اس کے نتیجہ میں ان کی
اہلی زندگی کامیاب اور بابرکت رہے گی ورنہ خواہ وہ سطحی اور عارضی خوشی حاصل کر لیں انہیں
کبھی بھی حقیقی اور دائمی راحت نصیب نہیں ہو سکتی.آنحضرت صلی الم کا یہ مبارک ارشاد
نہایت گہری حکمت پر مبنی ہے کیونکہ اس میں نہ صرف مسلمانوں کی اہلی زندگی کو بہترین بنیاد پر
قائم کرنے کا رستہ کھولا گیا ہے بلکہ ان کی آئندہ نسلوں کی حفاظت اور ترقی کا سامان بھی مہیا کیا
گیا ہے مگر افسوس ہے کہ دوسری اقوام تو الگ رہیں خود مسلمانوں میں بھی آج کل کثیر حصہ ان
لوگوں کا ہے جو بیوی کا انتخاب کرتے ہوئے یا تو دین اور اخلاق کے پہلو کو بالکل ہی نظر انداز
کر دیتے ہیں اور یا دین اور اخلاق کی نسبت دوسری باتوں کی طرف زیادہ دیکھتے ہیں.کوئی شخص
تو عورت کے حسن پر فریفتہ ہو کر باقی باتوں کی طرف سے آنکھیں بند کر لیتا ہے اور کوئی اس
کے حسب و نسب کا دلدادہ بن کر دوسری باتوں کو نظر انداز کر دیتا ہے اور کوئی اس کی دولت
کے لالچ میں آکر اس کے ہاتھ پر بک جانا چاہتا ہے حالانکہ اصل چیز جو اہلی زندگی کی دائمی خوشی
کی بنیاد بن سکتی ہے وہ عورت کا دین اور اس کے اخلاق ہیں.دنیا میں بے شمار ایسی مثالیں پائی
جاتی ہیں کہ ایک شخص نے کسی عورت کو محض اس کی شکل و صورت کی بناء پر انتخاب کیا لیکن
کچھ عرصہ گزرنے پر جب اس کے حسن و جمال میں تنزل کے آثار پید اہو گئے کیونکہ جسمانی
حسن ایک فانی چیز ہے یا اس کی نسبت کسی زیادہ حسین عورت کو دیکھنے کی وجہ سے بے اصول
خاوند کی توجہ اس کی طرف سے ہٹ گئی یا بیوی کے ساتھ شب وروز کا واسطہ پڑنے کے نتیجہ میں
اس کے عادات کے بعض ناگوار پہلو خاوند کی آنکھوں کے سامنے آگئے تو ایسی صورت میں
Page 87
75
زندگی کی خوشی تو در کنار خاوند کے لئے اس کا گھر حقیقتاً ایک دوزخ بن جاتا ہے اور یہی حال
ب و نسب اور دولت کا ہے کیونکہ حسب و نسب کی وجہ سے تو بسا اوقات بیوی کے دل میں
خاوند کے مقابلہ میں بڑائی اور تفاخر کا رنگ پیدا ہو جاتا ہے جو خانگی خوشی کے لئے مہلک ہے اور
دولت ایک آنی جانی چیز ہے جو آج ہے اور کل کو ختم ہو سکتی ہے اور پھر بسا اوقات یہ بھی ہوتا
ہے کہ بیوی کی دولت خاوند کے لئے ایک مصیبت ہو جاتی ہے اور راحت کا سامان نہیں بنتی.پس جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ ﷺ نے فرمایا ہے گھر یلو اتحاد اور گھر یلوخوشی کی حقیقی بنیاد عورت کے
دین اور اس کے اخلاق پر قائم ہوتی ہے اور بڑا ہی بد قسمت ہے وہ انسان جو ٹھوس اوصاف کو
چھوڑ کر وقتی کھلونوں یا ملمع سازی کی چیزوں کے پیچھے بھاگتا ہے.پھر ایک نیک اور خوش اخلاق بیوی کا جو گہرا اثر اولاد پر پڑتا ہے وہ تو ایک ایسی دائمی
نعمت ہے جس کی طرف سے کوئی دانا شخص جسے اپنی ذاتی راحت کے علاوہ نسلی ترقی کا بھی
احساس ہو آنکھیں بند نہیں کر سکتا.ظاہر ہے کہ بچپن میں اولاد کی اصل تربیت ماں کے سپرد
ہوتی ہے کیونکہ ایک تو بچپن میں بچہ کو طبعا ماں کی طرف زیادہ رغبت ہوتی ہے اور وہ اسی سے
زیادہ بے تکلف ہوتا ہے اور اسی کے پاس اپنا زیادہ وقت گزارتا ہے اور دوسرے باپ اپنے
دیگر فرائض کی وجہ سے اولاد کی طرف زیادہ توجہ بھی نہیں دے سکتا.پس اولاد کی ابتدائی
تربیت کی بڑی ذمہ داری بہر حال ماں پر پڑتی ہے.لہذا اگر ماں نیک اور با اخلاق ہو تو وہ اپنے
بچوں کے اخلاق کو شروع سے ہی اچھی بنیاد پر قائم کر دیتی لیکن اس کے مقابل پر ایک ایسی
عورت جو دین اور اخلاق کے زیور سے عاری ہے وہ کبھی بھی بچوں میں نیک اخلاق اور نیک
Page 88
76
عادات پیدا کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتی بلکہ حق یہ ہے کہ ایسی عورت بسا اوقات دین کی
اہمیت اور نیک اخلاق کی ضرورت کو سمجھتی ہی نہیں.پس نہ صرف خانگی خوشی کے لحاظ سے بلکہ
آئندہ نسل کی حفاظت اور ترقی کے لحاظ سے بھی نیک اور با اخلاق بیوی ایک ایسی عظیم الشان
نعمت ہے کہ دنیا کی کوئی اور نعمت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی.اسی لئے ہمارے آقا صلی ا یم
دوسری جگہ فرماتے ہیں:
خَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ
یعنی نیک بیوی دنیا کی بہترین نعمت ہے.“
مگر حدیث زیر نظر کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ بیوی کے انتخاب میں دوسری تمام باتوں کو
بالکل ہی نظر انداز کر دینا چاہیے بلکہ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ نیکی اور اخلاق کے پہلو کو
مقدم رکھنا چاہیے ورنہ بعض دوسرے موقعوں پر آنحضرت صلی ای ایم نے خود دوسری باتوں کی
طرف توجہ دلائی ہے کیونکہ وہ بھی ایک حد تک انسانی فطرت کے تقاضے ہیں مثلاً پر وہ کے احکام
کے باوجود آنحضرت صلی للہ کم فرمایا کرتے تھے کہ شادی سے پہلے اپنی ہونے والی بیوی کو دیکھ لیا
کرو تا کہ ایسا نہ ہو کہ بعد میں شکل و صورت کی وجہ سے تمہارے دل میں انقباض پیدا ہو 2 اور
ایک دوسرے موقع پر جب ایک عورت اپنی شادی کے متعلق آپ سے مشورہ لینے کی غرض
سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ نے فرمایا.میں تمہیں فلاں شخص سے شادی کا مشورہ
2
1 : مسلم کتاب الرضاع باب خير متاع الدنيا المراة الصالحة
: ابو داؤد کتاب النكاح باب فى الرجل ينظر الى المراة
Page 89
77
نہیں دیتا کیونکہ وہ مفلس اور تنگ دست ہے اور تمہارے اخراجات برداشت نہیں کر سکے گا
اور نہ میں فلاں شخص کے متعلق مشورہ دے سکتا ہوں کیونکہ اس کے ہاتھ کا ڈنڈا ہر وقت ہی اٹھا
رہتا ہے.ہاں فلاں شخص کے ساتھ شادی کر لو وہ تمہارے مناسب حال ہے ' اور ایک تیسرے
موقع پر آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ قبیلہ قریش کی عورتیں خاوند کی وفادار اور اولاد پر شفقت
کے حق میں اچھی ہوتی ہیں 2 اور ایک چوتھے موقع پر آپ نے فرمایا کہ حتی الوسع زیادہ اولاد پیدا
کرنے والی عورتوں کے ساتھ شادی کرو تا کہ میں قیامت کے دن اپنی امت کی کثرت پر فخر
کر سکوں.الغرض آپ نے اپنے اپنے موقع پر اور اپنی اپنی حدود کے اندر بعض دوسری باتوں
کی طرف بھی توجہ دلائی ہے لیکن جس بات پر آپ نے خاص زور دیا ہے وہ یہ ہے کہ ترجیح
بہر حال دین اور اخلاق کے پہلو کو ہونی چاہیے ورنہ تم اپنے ہاتھوں کو خاک آلود کرنے کے خود
ذمہ دار ہو گے.یہ وہ زریں تعلیم ہے جس پر عمل کر کے مسلمانوں کے گھر برکت و راحت کا
گہوارہ بن سکتے ہیں.کاش وہ اسے سمجھیں.1
: ابو داؤد کتاب الطلاق باب فى نفقة المبتوتة
2 : بخاری کتاب احادیث الانبیاء باب قولہ تعالیٰ اذ قالت الملائكة یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمة
3
: ابو داؤد کتاب النکاح باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء
Page 90
78
17
بہتر انسان وہ ہے
جو اپنی بیوی کے ساتھ بہتر سلوک کرے
عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ
اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ
لأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي
(سنن الترمذي ابواب الـ ، باب فی فضل ازواج النبی الام
ترجمہ : حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی العلیم فرماتے تھے:
تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ سلوک کرنے میں بہتر ہے اور میں اپنے اہل
کے ساتھ سلوک کرنے میں تم سب سے بہتر ہوں.تشریح: اس حدیث میں بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی جو تاکید کی گئی ہے وہ
ظاہر و عیاں ہے.آنحضرت صلی للی کم بیوی کے ساتھ خاوند کے حسن سلوک کو اتنی اہمیت دیتے
ہیں کہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم نے خدا اور اس کے رسول کو تو مان لیا اور ایمان کی نعمت سے بھی
متمتع ہو گئے لیکن حقوق العباد کے معاملہ میں اللہ تعالیٰ تمہارے ان اعمال کو بھی دیکھے گا جو تم
خدا کے بندوں کے ساتھ سلوک کرنے میں بجالاتے ہو اور ان اعمال میں بیوی کے ساتھ حسن
Page 91
79
سلوک کرنے کو اسلام میں بہت نمایاں درجہ حاصل ہے حتی کہ تم میں سے خدا کی نظر میں بہتر
انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں بہتر ہے لیکن چونکہ ہر شخص اپنے
سلوک کو بزعم خود اچھا قرار دے سکتا ہے اس لئے اس امکانی غلط فہمی کے ازالہ کے لئے
آنحضرت صلی ا کرم فرماتے ہیں کہ اچھے سلوک کا معیار تمہارا کوئی خود تراشیدہ قانون نہیں ہو گا
بلکہ اس معاملہ میں میرے نمونہ کو دیکھا جائے گا کیونکہ خدا کی دی ہوئی توفیق سے میں اپنے اہل
کے ساتھ سلوک کرنے میں تم سب سے بہتر ہوں.اس ارشاد کے ذریعہ آنحضرت صلی علی کریم نے مسلمان عورتوں کے ازدواجی حقوق کو
اتنے اعلیٰ معیار پر قائم فرما دیا ہے کہ وقتی رنجشوں کو چھوڑ کر جو بعض اوقات اچھے سے اچھے گھر
میں بھی ہو جاتی ہیں کوئی شریف بیوی کسی نیک مسلمان کے گھر میں دکھ کی زندگی میں مبتلا نہیں
ہو سکتی اور حق یہ ہے کہ اگر عورت کو خاوند کی طرف سے سکھ حاصل ہو تو وہ دنیا کی ہر دوسری
تکلیف کو خوشی کے ساتھ برداشت کرنے کے لئے تیار ہو جاتی ہے اور اس سکھ کے مقابلہ میں
کسی شریف عورت کے نزدیک دنیا کی کوئی اور نعمت کچھ حقیقت نہیں رکھتی لیکن اگر ایک
عورت کے ساتھ اس کے خاوند کا سلوک اچھا نہیں تو خاوند کی دولت بھی اس کے لئے لعنت ہے
اور خاوند کی عزت بھی اس کے لئے لعنت ہے اور خاوند کی صحت بھی اس کے لئے لعنت ہے
کیونکہ ان چیزوں کی قدر صرف خاوند کی محبت اور گھر کی سکینت کے میدان میں ہی پیدا ہوتی
ہے.پس اس بات میں ذرہ بھر بھی شک کی گنجائش نہیں کہ آنحضرت صلی للی کم کا یہ مبارک
ارشاد گھروں کی چار دیواری کو جنت بنا دینے کے لئے کافی ہے بشر طیکہ عورت بھی خاوند کی
Page 92
80
فرمانبرداری اور اس کی محبت کی قدر دان ہو اور پھر خاوند بیوی کے اس اتحاد کا اثر لازماً ان کی
اولاد پر بھی پڑتا ہے اور اس طرح آج کی برکت گویا ایک دائمی برکت کا پیش خیمہ بن جاتی
ہے.یہ وہ سبق ہے جو ہمارے آقا صلی الیکم نے آج سے چودہ سو سال قبل اس ملک میں اور
اس قوم کے درمیان رہتے ہوئے دیا جس میں عورت عموماً ایک جانور سے زیادہ حیثیت نہیں
رکھتی تھی اور پھر اس حکم کو دو ایسی باتوں کے ساتھ مربوط کر دیا جن کے بلند معیار تک آج کی
بظاہر ترقی یافتہ اقوام بھی نہیں پہنچ سکیں اور نہ کبھی پہنچ سکیں گی کیونکہ ان دو باتوں کے ساتھ
مل کر عورت کے ساتھ حسن سلوک کا حکم اس ارفع مقام کو حاصل کر لیتا ہے جس کے اوپر اس
میدان میں کوئی اور بلندی نہیں.یہ دوباتیں ہمارے آقا کے الفاظ
کے مطابق یہ ہیں کہ
خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُ كُمْ لِأَهْلِي
(اول) عورت کے ساتھ خاوند کا حسن سلوک صرف ضروری ہی نہیں ہے بلکہ
دراصل حقوق العباد کے میدان میں مرد کا یہی وصف خدا کی نظر میں مرد کے درجہ اور مقام کا
حقیقی پیمانہ ہے.جو شخص اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک میں بہتر ہے وہی خدا کی نظر میں بہتر
(دوم) اس حسن سلوک کا معیار کسی شخص کی ذاتی رائے پر مبنی نہیں ہے (کیونکہ اپنے
منہ سے تو ہر شخص اپنے آپ کو اچھا کہہ سکتا ہے) بلکہ اس کا معیار رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کا
Page 93
81
پاک اسوہ ہے.پس صرف وہی سلوک اچھا سمجھا جائے گا جو اس پاک اسوہ کے مطابق ٹھیک
اترے گا.
Page 94
82
18
دیندار عورت وہ ہے
جو اپنے خاوند کا حق ادا کرتی ہے
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْلَى قَالَ..فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ..وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا تُؤَذِي الْمَرْأَةُ حَقِّ رَيْهَا حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقٌّ زَوْجِهَا
(سنن ابن ماجه کتاب النکاح باب حق الزوج على المراة)
ترجمہ: عبد اللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی ا یکم فرماتے
تھے کہ مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے کہ کوئی عورت اس وقت
تک خدا تعالیٰ کا حق ادا کرنے والی نہیں سمجھی جا سکتی جب تک کہ وہ اپنے خاوند کا حق ادا نہیں
کرتی.تشریح: جہاں آنحضرت صلی این یکم نے ایک طرف خاوند کو بیوی کے ساتھ حسن سلوک کا
حکم دیا ہے وہاں دوسری طرف بیوی کو خاوند کے حقوق ادا کرنے کی بھی زبر دست تلقین فرمائی ہے
کیونکہ گھر کی حقیقی سکینت اور حقیقی برکت صرف اسی صورت میں قائم ہو سکتی ہے کہ خاوند بیوی
کے ساتھ بہترین سلوک کرنے والا ہو اور بیوی خاوند کے حقوق پوری پوری وفاداری کے ساتھ ادا
Page 95
83
کرے.آنحضرت صلی اللہ ہم کو عورت کے اس مقدس فریضہ کا اتنا خیال تھا کہ ایک دوسری حدیث
میں آپ فرماتے ہیں کہ جس مسلمان عورت کا خاوند ایسی حالت میں فوت ہو تا ہے کہ وہ اپنی بیوی
پر خوش ہے تو ایسی عورت خدا کے فضل سے جنت میں جائے گی اور اوپر والی حدیث کے دوسرے
حصہ میں فرماتے ہیں کہ اگر اسلام میں اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنا جائز ہو تا تو میں حکم دیتا کہ
عورت اپنے خاوند کو سجدہ کرے.اور یہ جو آنحضرت صلی الم نے فرمایا ہے کہ جو عورت اپنے خاوند کا حق ادا نہیں کرتی
وہ خدا کا حق بھی ادا نہیں کر سکتی.اس میں دو گہری حکمتیں ہیں.اول یہ کہ خواہ درجہ کا کتنا ہی فرق ہو یہ دونوں حقوق دراصل ایک ہی نوعیت کے ہیں
مثلاً جس طرح خدا اپنے بندوں سے انتہائی محبت کرنے والا ہے اسی طرح خاوند کو بھی اپنی بیوی
کے متعلق غیر معمولی محبت کا مقام حاصل ہوتا ہے اور جس طرح باوجود اس محبت کے خدا اپنے
بندوں کا حاکم اور نگران ہے اسی طرح خاوند بھی بیوی کی محبت کے باوجو د گھر کا نگران اور قوام
ہو تا ہے.پھر جس طرح خدا اپنے بندوں کا رازق ہے اور ان کی روزی کا سامان مہیا کر تا ہے اسی
طرح خاوند بھی اپنی بیوی کے اخراجات مہیا کرنے کا ذمہ دار ہے اور اسی طرح اور بھی کئی پہلو
مشابہت کے ہیں اور یہ مشابہت اتنی نمایاں ہے کہ ہماری زبان میں تو خاوند کو مجازی خدا کا نام دیا
گیا ہے اور لفظاً بھی خداوند اور خاوند ایک دوسرے سے بہت ملتے جلتے ہیں.1 : ابن ماجہ کتاب النكاح باب حق الزوج على المرأة
Page 96
84
دوسری حکمت اس میں یہ ہے کہ اسلام میں بندوں کے حقوق بھی خدا ہی کی طرف سے
مقرر شدہ ہیں اور شریعت نے حقوق العباد کو انتہائی اہمیت دی حتی کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ
خدا اپنے حقوق سے تعلق رکھنے والے گناہ تو معاف کر دیتا ہے مگر بندوں کے حقوق سے تعلق
رکھنے والے گناہ اس وقت تک معاف نہیں کرتا جب تک کہ خود بندے معاف نہ کریں.انہی دو
حکمتوں کی بناء پر آنحضرت صل للہ یکم فرماتے ہیں اور خدا کی قسم کھا کر بڑے زور دار الفاظ میں فرماتے
ہیں کہ کوئی عورت اس وقت تک خدا کے حقوق ادا کرنے والی نہیں سمجھی جاسکتی جب تک کہ وہ
اپنے خاوند کے حقوق ادانہ کرے اور پھر ان الفاظ میں یہ بھی اشارہ ہے کہ اس عورت پر خداراضی
نہیں ہو تا جو اپنے خاوند کے حقوق ادا نہیں کرتی.باقی رہا یہ سوال کہ بیوی پر خاوند کا حق کیا ہے.سو اس کے متعلق قرآن شریف اور
حدیث سے پتہ لگتا ہے کہ بیوی پر خاوند کا حق یہ ہے کہ وہ اس کی فرمانبر دار ہو.اس کا واجبی ادب
ملحوظ رکھے.اس سے محبت کرے.اس کی وفادار رہے.اس کی اولاد کی تربیت کا خیال رکھے.اس
کے مال کی حفاظت کرے اور جہاں تک ممکن ہو اس کی خدمت بجالائے.اس کے مقابل پر خاوند
پر بیوی کا حق یہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ محبت اور شفقت اور دلداری سے پیش آئے.اس کے
آرام کا خیال رکھے.اس کے جذبات کا احترام کرے اور اپنی حیثیت کے مطابق اس کے ضروری
اخراجات کا کفیل ہو.اب ہر شخص خود سوچ سکتا ہے کہ اگر مرد اور عورت ایک دوسرے کے
متعلق ان حقوق کا خیال رکھیں تو مسلمانوں کے گھروں کو جنت بننے میں کیا کسر رہ جاتی ہے؟
Page 97
85
19
قیموں کی پرورش کرنے والا انسان جنت میں
رسول پاک کے ساتھ ہو گا
عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَكَافِلُ
اليتيم في الجنةِ كَهَاتَني وَأَشَارَ بِأَصْبَعَيْهِ يَعْنِي: السَّبَابَةَ والوسطى.(سنن الترمذي ابواب البر والصلة باب ما جاء في رحمة اليتيم وكفالته )
ترجمہ : سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
فرماتے تھے کہ میں اور یتیم کی پرورش اور حفاظت کرنے والا مسلمان جنت میں اس طرح ہوں
گے جس طرح کہ میری یہ دو انگلیاں ہیں اور یہ فرماتے ہوئے آپ نے اپنے ہاتھ کی دو انگلیاں
اٹھا کر باہم پیوست کر دیں.تشریح: یتیم بچے قوم کا ایک نہایت قیمتی خزانہ ہوتے ہیں اور اسلام نے یتیموں کی
پرورش اور حفاظت کے متعلق انتہائی تاکید کی ہے.چنانچہ اس حدیث کے الفاظ اس غیر معمولی
تاکید کے علم بردار ہیں.آنحضرت صلی اللہ یکم یتیم کی حفاظت کرنے والے مسلمان کے متعلق
Page 98
86
فرماتے ہیں کہ وہ جنت میں میرے اس قدر قریب ہو گا جس طرح ایک ہاتھ کی دو انگلیاں ایک
دوسرے کے قریب ہوتی ہیں.اس تاکیدی حکم کے بعد جس کے ساتھ ایک غیر معمولی انعام
بھی وابستہ ہے کوئی سچا مسلمان یتیموں کی پرورش اور حفاظت کی طرف سے غافل نہیں ہو سکتا.یتیموں کی نگہداشت میں صرف بے بس اور بے سہارا بچوں کی حفاظت اور تربیت کا پہلو ہی
مقصود نہیں ہے بلکہ اگر غور کیا جائے تو اس ذریعہ سے قوم کے افراد میں ترقی کی روح بھی ترقی
کرتی ہے.جس قوم کے افراد اس بات کا یقین رکھتے ہوں کہ اگر وہ قومی خدمت بجالاتے
ہوئے فوت ہو گئے تو ان کے پیچھے ان کی یتیم اولاد بے بس اور بے سہارا نہیں رہ جائے گی بلکہ
ان کے رشتہ دار اور قوم کے دوسرے افراد ان کے یتیم بچوں کے پوری طرح کفیل ہوں گے تو
وہ لاز ماہر قربانی کے لئے جرات کے ساتھ قدم اٹھائیں گے اور اس طرح قوم کے افراد میں قومی
خدمت اور قربانی کی روح ترقی کرے گی.پس یتیموں کی حفاظت کا انتظام صرف نابالغ بچوں کو
روحانی اور اخلاقی اور مالی تباہی سے بچانے کا ذریعہ ہی نہیں ہے بلکہ قوم کی مجموعی ترقی اور قوم میں
قربانی کی روح کو فروغ دینے کا بھی بھاری ذریعہ ہے.مگر افسوس ہے کہ آج کل مسلمانوں میں اس مقدس فریضہ کی طرف سے سخت غفلت
برتی جاتی ہے.بسا اوقات قریبی رشتہ دار یتیموں کے محافظ بننے کی بجائے ان کے اموال کو لوٹنے
اور انہیں غفلت کی حالت میں چھوڑ کر تعلیمی اور تربیتی لحاظ سے تباہ کرنے کا باعث بن جاتے ہیں اور
جو یتیم خانے مختلف اداروں کی طرف سے قائم ہیں ان میں عموماً یتیموں کے جذبات خود داری اور
عزت نفس کو بری طرح کچلا جاتا ہے اور یتیم بچے بھک منگے فقیر بن کر رہ جاتے ہیں.
Page 99
87
پس اس معاملہ میں بڑی اصلاح کی ضرورت ہے.جو رشتہ دار اپنے عزیز یتیموں کے ولی
قرار پائیں ان کا فرض ہے کہ ان کی تعلیم و تربیت اور ان کے کیریکٹر کی بلندی اور ان کے اموال کی
حفاظت کا پورا پورا اہتمام کریں اور جو ادارے اس کام کو اپنے ہاتھ میں لیں ان کے کارکنوں کا فرض
ہے کہ یتیم بچوں کے لئے باپ کی طرح بن کر رہیں اور انہیں در در کے سوالی بنانے کی بجائے قوم
کے خود دار اور مفید ممبر بنانے کی تدبیر اختیار کریں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کے دلوں
میں یہ احساس نہ پیدا ہونے دیں کہ ہم گویا بے بس اور بے کس ہو کر دوسروں کی خیرات پر پڑے
دوسری طرف یتیم بچوں کے لئے بھی مایوسی کی کوئی وجہ نہیں.انہیں یہ بات ہمیشہ یاد
رکھنی چاہیے کہ دنیا کا سب سے بڑا انسان سید الکونین فخر الانبیاء علی الی کی بھی ایک یتیم تھا اور یتیم
بھی وہ جس کا باپ اس کی پیدائش سے پہلے فوت ہو گیا تھا اور اس کی ماں بھی اسے چھ سات سالہ
بچھہ چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو گئی تھی.پس اگر وہ نیکی کا راستہ اختیار کریں گے تو یقینا خدا انہیں
بھی ہر گز ضائع نہیں کرے گا اور خدا سے بڑھ کر کس کی کفالت ہو سکتی ہے.
Page 100
88
20
ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک کی انتہائی تاکید
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا زَالَ
جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ ، حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرّثُهُ.(صحيح البخاري كتاب الادب باب الوصاة بالجار)
ترجمہ : حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علم فرماتے تھے کہ
جبریل نے مجھے ہمسایہ کے متعلق خدا کی طرف سے بار بار اتنی تاکید کی ہے کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ
شاید وہ اسے وارث ہی قرار دے دے گا.تشریح: ہمسائے بھی انسانی سوسائٹی میں اہم حصہ ہوتے ہیں اور آنحضرت صلی للی یکم
نے ہمسایوں کے ساتھ نیک سلوک کی سخت تاکید فرمائی ہے.حق یہ ہے کہ جو شخص اپنے ہمسایہ
کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا وہ دراصل انسان کہلانے کا حق دار ہی نہیں کیونکہ انسان ایک
متمدن مخلوق ہے اور ہمسایگت تمدن کا ایک لازمی اور ضروری حصہ ہے.پس باہمی تعلقات کی
بہتری اور مضبوطی کے لئے اسلام حکم دیتا ہے کہ ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے اور
اس حکم میں اس قدر تاکید کا پہلو اختیار کرتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ یکم فرماتے ہیں کہ جبریل نے
Page 101
89
مجھے اس بارے میں اس طرح تکرار اور تاکید کے ساتھ کہا کہ میں نے خیال کیا کہ شاید ہمسایہ
کو وارث ہی بنادیا جائے گا.اس تاکیدی حکم کے پیش نظر ہر سچے مسلمان کا فرض ہے کہ وہ
اپنے ہمسایوں کے ساتھ خاص محبت اور احسان کا سلوک کرے اور ان کے دکھ سکھ میں شریک
ہو اور ان کی غیر حاضری میں ان کے بیوی بچوں کا خیال رکھے.آنحضرت صلی اللہ کم کو ہمسایوں
کے ساتھ حسن سلوک کا اتنا خیال تھا کہ آپ چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی اس کی تاکید فرماتے
تھے.چنانچہ ایک دوسری حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ جب تم گھر میں گوشت وغیر ہ پکاؤ تو
شور به زیاده کر دیا کرو تا تمہارا کھانا حسب ضرورت تمہارے ہمسایہ کے کام بھی آسکے.دراصل انسان کے اخلاق کا اصل معیار اس کا وہ سلوک ہے جو وہ اپنے ہمسایوں کے
ساتھ کرتا ہے.دور کے لوگوں اور کبھی کبھار ملنے والوں کے ساتھ تو انسان تکلف کے رنگ
میں وقتی اخلاق کا اظہار کر دیتا ہے مگر جن لوگوں کے ساتھ اس کا دن رات کا واسطہ پڑتا ہے ان
کے ساتھ تکلف نہیں چل سکتا اور انسان کے اخلاق بہت جلد اپنی اصلی صورت میں عریاں ہو
کر لوگوں کے سامنے آجاتے ہیں.پس آنحضرت صلی اللہ علم کا یہ مبارک ارشاد جو اس حدیث میں درج ہے ہمسایوں کے
ساتھ حسن سلوک کی تلقین کے علاوہ بالواسطہ طور پر خود سلوک کرنے والوں کے اپنے اخلاق
کی درستی کا بھی ایک عمدہ ذریعہ ہے کیونکہ ہمسایوں کے ساتھ وہی شخص اچھا سلوک کر سکتا ہے
جس کے اپنے اخلاق حقیقتاً اچھے ہوں کیونکہ ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے لئے
1 : مسلم كتاب البر والصلة باب الوصية بالجار والاحسان الیہ
Page 102
90
ص کو لازما خود بھی اچھا بنا پڑے گا.ورنہ شب و روز ملنے والوں کے ساتھ تکلف کا
پیراہن زیادہ دیر تک چاک ہونے سے بچ نہیں سکتا.اسی طرح اس حدیث کے وسیع معنوں کے مطابق قوموں اور ملکوں پر بھی یہ فرض
عائد ہوتا ہے کہ حتی الوسع اپنی ہمسایہ قوموں اور ملکوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور ان کے
ساتھ احسان اور تعاون کا معاملہ کریں کیونکہ جس طرح ایک فرد اخلاق کے قانون کے ماتحت
ہے اسی طرح قومیں بھی اس قانون کے ماتحت ہیں اور حق یہ ہے کہ دنیا میں امن تبھی قائم
ہو سکتا ہے کہ جب قومیں اور حکومتیں بھی اپنے آپ کو اخلاق کے قانون کا کار بند سمجھیں.
Page 103
91
21
جنگ کی تمنانہ کرو لیکن اگر لڑائی ہو جائے
تو ڈٹ کر مقابلہ کرو
عن أبي النظر عن كِتَابِ رَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ مِنْ أَعْمَابِ النَّبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يُقَالُ لَهُ: عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي أَوْلَى فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ حِينَ سَارَ
إلى الحرُورِيَّةِ يُخْبِرُهُ، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ....فَقَالَ: يَا أَيُّهَا
النَّاسُ! لَا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُةِ، وَاسْأَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ
فَاصْبِرُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلالِ السُّيُوفِ.( صحیح مسلم کتاب الجهاد والسير باب كراهة تمنى لقاء العدو......)
ترجمہ : عبد اللہ بن ابی اوفیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تم نے
صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا.اے مسلمانو! دشمن کے مقابلہ کی کبھی تمنانہ کیا کرو اور خدا سے
امن اور عافیت کے خواہاں رہو لیکن جب دشمن کے ساتھ ٹکراؤ ہو جائے تو پھر صبر اور
استقلال کے ساتھ مقابلہ کرو اور یاد رکھو جنت تلواروں کے سایہ کے نیچے ہے.
Page 104
92
تشریح: یہ حدیث دشمنوں کے ساتھ حسن سلوک اور فلسفہ جہاد کے متعلق اسلامی
تعلیم کا نہایت لطیف خلاصہ پیش کرتی ہے جو چہار اصولی باتوں میں آجاتا ہے.(i) دشمن کے ساتھ لڑنے کی کبھی خواہش نہ کرو اور نہ اس پر حملہ کرنے میں اپنی
طرف سے پہل کرو.(ii) ہمیشہ خدا سے امن اور عافیت کے خواہاں رہو.(iii) اگر دشمن کی طرف سے پہل ہونے پر اس کے ساتھ لڑائی کی صورت پیدا
ہو جائے تو پھر کامل صبر اور استقلال کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کرو.(iv) مقابلہ کی صورت میں تسلی رکھو کہ دو انعاموں میں سے ایک انعام بہر حال تم
کو مل کر رہے گا یعنی یاتو تم فتح پاؤ گے اور یا شہادت حاصل کرو گے.جنگوں کے متعلق خواہ وہ دینی ہوں یاد نیوی، دنیا کا کوئی مذہب اور کوئی ملک اور تاریخ
عالم کا کوئی زمانہ اس سے بہتر ضابطہ اخلاق پیش نہیں کر سکتا اور ضمناً اس حدیث سے یہ بھی
ثابت ہو تا ہے کہ اسلام دین کے معاملہ میں جبر کی ہر گز اجازت نہیں دیتا کیونکہ اگر لوگوں کو
جبر أمسلمان بنانے کی اجازت ہوتی تو آنحضرت صلی اللہ کی بھی یہ ارشاد نہ فرماتے کہ تم دشمن کے
مقابلہ کی خواہش نہ کرو.جبر کرنے والا تو خود موقع تلاش کر کر کے دوسروں پر حملہ آور ہوتا
ہے تا کہ انہیں مغلوب کر کے اپنے رنگ میں ڈھال لے.پس آپ کا یہ فرمانا کہ کبھی دشمن کے مقابلہ کی خواہش نہ کرو اس بات کی قطعی دلیل
ہے کہ اسلام دین کے معاملہ میں قطعاً جبر کی اجازت نہیں دیتا اور یہ وہی تعلیم ہے جو قرآن
Page 105
93
شریف نے ان الفاظ میں صراحتا بیان فرمائی ہے کہ لا إكراه في اللاتين ! یعنی دین کے معاملہ
میں جبر کرنا ہر گز جائز نہیں.پھر ایک طرف مسلمانوں کو پہل کرنے سے روکنا اور دوسری طرف انہیں صبر کے
ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی تلقین کرنا اس لطیف حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ گو اسلام
مسلمانوں کو ظالم بننے سے بہر حال روکتا ہے مگر وہ مسلمانوں کے دلوں سے موت کا خوف بھی
قطعی طور پر نکالنا چاہتا ہے اور یہی وہ وسطی تعلیم ہے جو قوموں کی ترقی کی بنیاد بنا کرتی ہے کہ
ایک طرف تو وہ اپنے نفسوں کو روک کر رکھیں اور کسی صورت میں بھی ظالم نہ بنیں اور دوسری
طرف وہ موت کے سامنے ایسے بہادر اور بے خطر ہوں کہ تلواروں کے سایہ میں جنت کا نظارہ
دیکھیں.1 : البقرة 257
Page 106
94
22
1
دشمن سے بد عہدی نہ کرو
اور بچوں اور عورتوں کے قتل سے بچو
عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةً عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَمَرَ
أمرينا على جيش أو سرية أو صاد قال الرواياتي الله فَلا تَلُوا وَلَا تَعْبُدُوا وَلَا
تمعلُوا وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا..لا تَقْتُلَنَ امْرَأَةً.(صحیح مسلم كتاب الجهاد والسير باب تأمير الامام الامراء على البعوث ووصية اياهم.ترجمه: بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی الم صحابہ کی کوئی
پارٹی جہاد کے لئے روانہ فرماتے تو اس کے امیر کو نصیحت فرماتے تھے کہ اللہ کا نام لے کر خدا
کے رستہ میں نکلو اور کبھی خیانت نہ کرو اور نہ کبھی دشمن سے بد عہدی کرو اور نہ قدیم وحشیانہ
طریق کے مطابق دشمن کے مقتولوں کے اعضاء وغیرہ کاٹو اور نہ کسی بچے یا عورت کو قتل کرو.: لا تَقْتُلَنَّ امْرَأَةٌ : یہ الفاظ موطاء امام مالک سے لئے گئے ہیں.منہ ،
(موطاء (بروایت یحی بن یحی) کتاب الجهاد باب النهي عن قتل النساء والولدان )
Page 107
95
تشریح: آنحضرت صلی علیکم کا یہ مبارک ارشاد ابتدائی جنگوں میں صحابہ اور ان کے بعد
آنے والے مسلمانوں کا طرہ امتیاز رہا ہے.اسلام نے کفار کے مظالم اور ان کی جارحانہ
کارروائیوں سے مجبور ہو کر تلوار اٹھائی لیکن اس کے بعد مسلمانوں نے ظالم دشمن کے ساتھ
بھی حسن اخلاق کا وہ نمونہ دکھایا جس کی نظیر پیش کرنے سے تاریخ عاجز ہے.عربوں میں
عور توں اور بچوں تک کو قتل کر دینے کا طریق عام تھا بلکہ یہ طریق موسوی شریعت کے قیام سے
دنیا کے معتد بہ حصہ میں وسیع ہو چکا تھا اور اس کے علاوہ عربوں میں یہ بھی رواج تھا کہ مفتوح
دشمن کے مقتولوں کے ناک، کان وغیرہ کاٹ کر اپنی وحشیانہ خوشی کو کمال تک پہنچاتے تھے.اس فتیح رسم کو عرب لوگ مثلہ کرنا کہتے تھے.آنحضرت صلی ا ہم نے ان سب ظالمانہ طریقوں
کو سختی کے ساتھ روک کر حربی دشمن کے ساتھ بھی حسن سلوک کی تعلیم دی اور خیانت اور
غداری اور بد عہدی کو قطعی حرام قرار دے کر دنیا میں ایک اعلیٰ ضابطہ اخلاق کی بنیاد قائم کی.اس کے علاوہ جیسا کہ دوسری احادیث سے ثابت ہے آنحضرت صلی الیم نے یہ بھی
حکم دیا کہ حربی دشمن کے بوڑھے لوگوں اور مذہبی خدمت کے لئے اپنی زندگیوں کو وقف
کرنے والوں کے خلاف خواہ وہ کسی مذہب و ملت کے ہوں ہاتھ نہ اٹھایا جائے ' اور جیسا کہ
قرآن شریف کی سورۃ محمد میں فرماتا ہے 2 جنگی قیدیوں کے متعلق بھی حکم دیا ہے کہ انہیں
قتل نہ کیا جائے بلکہ یا تو انہیں بطور احسان چھوڑ دیا جائے اور یا واجبی فدیہ لے کر رہا کر دیا جائے
: سنن الكبرى للبيهقى ، كتاب السير ، جماع ابواب السیر ، باب ترک القتل من لاقتال فيه من الرهبان...2 : محمد: 4
Page 108
96
اور بہر حال جنگ کے اختتام کے بعد ان کی قید کو لمبانہ کیا جائے اور دوران قید بھی جنگی قیدیوں
کے ساتھ اسلام نے حسن سلوک کا اس تاکید کے ساتھ حکم دیا کہ خود غیر مسلم قیدیوں کی
روایت ہے کہ مسلمان ہمیں اچھا کھانا دیتے تھے اور خود معمولی خوراک پر گزارہ کرتے تھے.ہمیں اونٹوں پر سوار کرتے تھے اور خود پیدل چلتے تھے.کیا کسی حربی دشمن کے ساتھ دنیا کی
کسی قوم نے تاریخ کے کسی زمانہ میں اس سے بہتر سلوک کیا ہے؟
ہے.باقی رہاد شمن کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ سواس کے متعلق قرآن شریف فرماتا
لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
یعنی اے مسلمانو! کسی قوم کی دشمنی تمہیں ہر گز اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم اس
کے متعلق عدل و انصاف کے رستہ سے ہٹ جاؤ بلکہ تمہیں چاہیے کہ ہر حال میں دشمن کے
ساتھ بھی عدل و انصاف کا سلوک کرو کہ یہی تقویٰ کا تقاضا ہے.66
مگر افسوس کہ دنیا نے اس شان دار تعلیم کی قدر نہیں کی.1 : المائدة: 9
Page 109
97
23
عَنْ
سات تباہ کرنے والی چیزیں
(قتل ناحق سود خوری.بہتان تراشی وغیرہ)
أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اجْتَنِبُوا السَّبْعَ
المُوبِقَاتِ، قَالُوا : يَارَسُولَ اللهِ، وَمَا هُنَّ قَالَ: المركُ بِاللهِ وَالسِّحْرُ ، وَقَتْلُ
النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالحَقِّ، وَأَكُلُ الرِّبَا وَأَكُلُ مَالِ اليَتِيمِ ، وَالتَّوَلِّي
يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذَفُ المُحْصَنَاتِ المُؤْمِنَاتِ الغَافِلَاتِ
(صحيح البخاري كتاب الحدود باب رمى المحصنات
ترجمہ: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے
تھے کہ اے مسلمانو! تمہیں سات تباہ کرنے والی باتوں سے ہمیشہ بچ کر رہنا چاہیے.صحابہ نے
عرض کیا.یار سول اللہ ! یہ سات باتیں کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا.(۱) کسی کو خدا تعالیٰ کا
شریک ٹھہرانا (۲) نظر فریب باتوں کے پیچھے لگنا (۳) کسی انسان کو ناحق قتل کرنا (۴) سود
Page 110
98
کھانا (۵) یتیم کا مال غصب کرنا (۶) جنگ میں دشمن کے سامنے پیٹھ دکھانا اور (۷) بے گناہ
مومن عورتوں پر بہتان باندھنا.تشریح: اس حدیث میں آنحضرت صلی للی یکم نے سات ایسی باتیں بیان فرمائی ہیں جو
بالآخر افراد اور قوموں کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہیں.سب سے پہلی اور سب سے زیادہ اہم بات
شرک ہے جس کے معنی خدا کی ذات و صفات میں کسی دوسرے کو شریک قرار دینا ہے.شرک ایمانیات کے میدان میں جرم نمبر ایک کا حکم رکھتا ہے اور بالواسطہ طور پر شرک کے
نتیجہ میں اخلاق پر بھی بھاری اثر پڑتا ہے.شرک دو قسم کا ہے.ایک شرک ظاہر ہے اور
دوسرے شرک خفی.شرک ظاہر تو یہ ہے کہ کسی انسان یا کسی دوسری چیز کو خدا کے برابر یا
خدائی حکومت میں حصہ دار یا خدائی صفات کا مالک قرار دیا جائے جیسا کہ مثلاً ہند و خدا کے علاوہ
بہت سے دیوتاؤں کو مانتے ہیں اور انہیں خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں یا جیسا کہ عیسائی حضرت
عیسی علیہ السلام کو خدا کا بیٹا اور اس کی صفات اور حکومت میں حصہ دار یقین کرتے ہیں اور
شرک خفی یہ ہے کہ بظاہر تو خدا کا کوئی شریک نہ ٹھہرایا جائے اور خدا کی توحید کا مدعی بنایا جائے
مگر عملاً کسی دوسری چیز کی ایسی عزت کی جائے جو صرف خدا کی کرنی چاہیے یا کسی دوسری چیز پر
ایسا بھروسہ کیا جائے جو صرف خدا کی شایان شان ہے یا کسی دوسری چیز کے ساتھ ایسی محبت کی
جاۓ جو صرف خدا کے ساتھ ہونی چاہیے یا کسی دوسری چیز سے ایساڈرایا جائے جو صرف خدا کا
حق ہے.اس قسم کا مخفی شرک بد قسمتی سے آج کل بہت مسلمانوں میں بھی پایا جاتا ہے.اسلام
ان دونوں قسم کے شرکوں یعنی شرک ظاہر اور شرک خفی سے بچنے کا حکم دیتا ہے اور ایک
Page 111
99
دوسری حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ شرک کے اجتناب یعنی توحید کے مفہوم میں خدا
پر ایمان لانے کے علاوہ رسول اللہ صلی للی کمر پر ایمان لانا بھی شامل ہے کیونکہ رسالت ہی کے
ذریعہ دنیا میں حقیقی توحید قائم ہوتی ہے.بہر حال اسلام میں شرک کے خلاف انتہائی تاکید پائی
جاتی ہے اور ہر سچے مسلمان کا فرض ہے کہ شرک ظاہر اور شرک خفی دونوں سے بچ کر رہے.شرک خفی کے متعلق حضرت مسیح موعود بانی سلسلہ احمدیہ کس لطیف انداز میں فرماتے ہیں کہ
ہر چہ غیرے خدا بخاطر تست آن بت تست اے بایمان سست
پر حذر باش زین بتان نهان دامن دل ز دست شان بربان
یعنی ہر وہ چیز جو تیرے دل میں خدا کے مقابل پر جاگزیں ہے وہ تیرابت ہے اے
ست ایمان والے شخص ! تجھے چاہیے کہ ان مخفی بتوں کی طرف سے ہوشیار رہے اور اپنے دل
کے دامن کو ان بتوں سے بچا کر رکھ.دوسری بات اس حدیث میں سحر بیان کی گئی ہے.سحر کے معنی عربی زبان میں ایسی
چیز کے ہیں جو نظر فریب ہو یعنی جس میں ایک چیز کی اصل حقیقت پر پردہ ڈال کر اسے دوسری
شکل میں پیش کر دیا جائے اور جھوٹ کو سچ بنا کر دکھایا جائے.اس قسم کا سحر جھوٹ کی ایک بد
ترین قسم ہے کیونکہ اس میں جھوٹ کے ساتھ دھو کے اور چالا کی کا عنصر بھی شامل ہو جاتا ہے.اسی لئے عربی میں ملمع سازی کو بھی سحر کہتے ہیں مثلاً جب ایک چاندی کی چیز پر سونے کا پانی پھیر
ابراہین احمدیہ ، روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 127,128
Page 112
100
کر اسے سونے کے طور پر پیش کیا جائے تو اسے عربی میں سحر کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے.اسی طرح عربی میں اس چیز کو بھی سحر کہتے ہیں جس میں فریب کے طریق پر اخفاء اور راز داری
کا رنگ اختیار کیا جائے.اسلام ان سب باتوں کو ناجائز قرار دیتا ہے کیونکہ یہ چیزیں اخلاق پر
نہایت برا اثر ڈالنے والی، عادات کو پیچیدہ بنانے والی اور آپس میں بد گمانی اور تفرقہ اور انشقاق
پیدا کرنے والی ہیں اور عرف عام والے سحر کی ملمع سازی اور دھوکا دہی تو ظاہر وعیاں ہے جس
کے متعلق کسی تشریح کی ضرورت نہیں.علاوہ ازیں سحر کے معنی فتنہ وفساد کے بھی ہیں اور
اس صورت میں بھی سحر کی خرابی ایک بدیہی امر ہے اور اگلے فقرہ میں قتل کا ذکر اس مفہوم پر
ایک عمدہ قرینہ ہے.تیسری بات قتل ناحق بیان کی گئی ہے.اسلام نے قتل کو کبیرہ گناہوں میں شمار کیا ہے
اور قتل عمد کی سزا موت مقرر کی گئی ہے جسے سوائے ایسی صورت کے بدلا نہیں جاسکتا کہ جب
فریقین اصلاح کے خیال سے موت کی سزا کو دیت یعنی خون بہا کی صورت میں بدلنے پر
رضامند ہو جائیں اور حاکم وقت بھی اسے منظور کرلے اور یہ رعایت اس حکمت کے ماتحت رکھی
گئی ہے کہ تا اگر فریقین کے خاندانوں میں اصلاح کی حقیقی امید موجود ہو تو بلا وجہ قتل کی سزا پر
زور دے کر دو خاندانوں کو انتقام در انتقام کے چکر میں نہ ڈالا جائے.اور قتل کے ساتھ ناحق “
کی شرط اس لئے رکھی گئی ہے کہ تا جنگ میں قتل ہونے والوں یا حکومت کے قانون کے ماتحت
قتل کی باضابطہ سزا پانے والوں کی استثناء قائم رہے.قتل ناحق میں ایسے قتل بھی شامل ہیں جو
بعض مغلوب الغضب افراد یا مذ ہی دیوانے کسی شخص کو بزعم خود قتل کی سزا کا مستحق سمجھ کر
Page 113
101
اسے باضابطہ عدالت میں لے جانے کے بغیر خود بخود قتل کر دیتے ہیں.اسلام اس قسم کی
دست درازی اور قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کے طریق کو بھی بڑی سختی کے ساتھ روکتا ہے
کیونکہ اس قسم کے حکم کے بغیر بھی ملک کا امن قائم نہیں رہ سکتا.در حقیقت قتل ناحق کے
جرم کو اسلام نے انتہا درجہ خطرناک قرار دیا ہے حتی کہ ایک جگہ قرآن شریف فرماتا ہے کہ
”جس شخص نے ایک جان کو ناحق قتل کیا اس نے گویا سارے جہان کو قتل کیا کیونکہ قتل
کے نتیجہ میں نہ صرف انتقام در انتقام کا لمبا تسلسل اور گندہ دور قائم ہو جاتا ہے بلکہ ملک میں
قانون کا احترام بھی بالکل مٹ جاتا ہے اور اس قسم کے واقعات کے نتیجہ میں انسانی ضمیر
دہشت زدہ ہو کر آہستہ آہستہ بالکل مر جاتا ہے.پس ضروری تھا کہ قتل کو انتہا درجہ کے
جرموں میں شمار کیا جائے.چوتھی بات اس حدیث میں سود بیان کی گئی ہے.بے شک صدیوں کے غیر اسلامی
ماحول کی وجہ سے آج کل سود قریباً ساری دنیا کے اقتصادی نظاموں کا جزولاینفک قرار پاچکا ہے
اور خود مسلمانوں کا ایک معتدبہ حصہ بھی اس میں بالواسطہ یا بلا واسطہ ملوث ہے مگر اس میں ذرہ
بھر شبہ نہیں کہ سود ایک بھاری لعنت ہے جو نہ صرف انسانی ہمدردی اور موالات کے جذبات
کے لئے تباہ کن ہے بلکہ دنیا میں جھگڑوں اور لڑائیوں کی آگ کو بھڑ کانے کا بھی بہت بڑا
موجب ہے.سود کے نتیجہ میں (۱) انسانی فطرت کے لطیف اخلاق تباہ ہوتے ہیں (۲) اپنی
1 المائدة: 33
Page 114
102
طاقت سے زیادہ قرض برداشت کرنے کی جرات پید اہوتی ہے اور (۳) لڑائیوں اور جنگوں کو
ناواجب طول حاصل ہوتا ہے کیونکہ دشمنی کے جوش میں اندھے ہو کر لوگ بے تحاشہ قرض
لیتے اور لڑائی کی آگ کو بپا کرتے چلے جاتے ہیں.اس لئے اسلام نے سود کو حرام قرار دے کر
قرضہ کے لین دین کو ذیل کی تین صورتوں میں محدود کر دیا ہے.(اوّل) سادہ قرضہ جسے عرف عام میں قرضہ حسنہ کہتے ہیں.جس طرح ایک رشتہ دار
دوسرے رشتہ دار کو یا ایک دوست دوسرے دوست کو یا ایک ہمسایہ دوسرے ہمسایہ کو
ضرورت کے وقت قرضہ دیتا ہے.(دوسرے) قرضہ بصورت رہن یعنی اپنی کوئی جائیداد منقولہ یا غیر منقولہ رہن رکھ
کر اس کی ضمانت پر کچھ رقم قرض لے لی جائے اور
(تیسرے) تجارتی شرکت یعنی کسی شخص کو اپناروپیہ تجارت یا صنعت و حرفت کی
صورت دے کر اس کے ساتھ نفع و نقصان میں شرکت کا فیصلہ کر لیا جائے.ان تین صورتوں کے سوا اسلام کسی اور قرض کی اجازت نہیں دیتا اور سود کے لینے
اور دینے کو ( خواہ اس کی شرح کم ہو یا زیادہ) حرام اور ممنوع قرار دیتا ہے.یہ خیال کرنا کہ سود
کے بغیر گزارہ نہیں چلتا ایک باطل خیال ہے جو محض آجکل کے باطل ماحول کی وجہ سے پید اہوا
ہے ورنہ اسلامی غلبہ کے زمانہ میں دنیا کی وسیع تجارت سود کے بغیر ہی چلتی تھی اور ان شاء اللہ
آئندہ بھی جب کہ اسلام کے دوسرے غلبہ کا دور آئے گا اور لوگ ٹھوکریں کھا کھا کر بیدار
ہوں گے پھر اسی طرح چلا کرے گی.
Page 115
103
پانچویں بات یتیم کا مال کھانا بیان کی گئی ہے.یہ گناہ بھی خاندانوں اور قوموں کو تباہ
کر کے رکھ دیتا ہے کیونکہ اس کے نتیجہ میں ایک تو قوم کے نو نہال تباہ ہو جاتے ہیں.دوسرے
ہمدردی کا جذبہ متا اور بد دیانتی کا جذبہ ترقی کرتا ہے.تیسرے کمزور جنس پر ظلم کا رستہ کھلتا ہے
اور چوتھے قوم میں سے قربانی کی روح بھی مٹنی شروع ہو جاتی ہے.یقینا اس قوم کے افراد کبھی
بھی جرات کے ساتھ قربانی کی طرف قدم نہیں اٹھا سکتے جن کی آنکھوں کے سامنے یتیموں
کے لٹنے اور برباد ہونے کے نظارے پیش آتے رہیں کیونکہ اس صورت میں طبعاً ان کے اندر یہ
ڈر پیدا ہو گا کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے یتیم بچوں کے ساتھ بھی یہی سلوک ہو گا.پس
یتیموں کی ہمدردی اور یتیموں کے مال کی حفاظت اسلام میں ایک نہایت اہم ذمہ داری قرار دی
گئی ہے اور قرآن شریف نے اس پر انتہائی زور دیا ہے.چھٹی بات لڑائی کے میدان میں دشمن کو پیٹھ دکھانا ہے.یہ کمزوری بھی قوموں کی
تباہی میں بھاری اثر رکھتی ہے.حق یہ ہے کہ کوئی بزدل قوم زندہ رہنے کے قابل نہیں ہوتی اور
بڑی آسانی سے ظالم اور جابر قوموں کا شکار ہو جاتی ہے اس لئے اسلام نے میدان جنگ میں پیٹھ
دکھانے اور بھاگنے کو کبیرہ گناہوں میں شمار کیا ہے.چنانچہ قرآن شریف فرماتا ہے.يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حُفَّا فَلَا تُوَلُوهُمُ الْأَدْبَارَ
وَمَن تُوَلِّهِمْ يَومين دارَ الَّا مُتَحَرَّ فَالْقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيْرًا إِلَى فِقَةٍ
Page 116
104
فقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَا وُهُ جَهَنَّمُ
یعنی اے مومنو! جب تم کافروں کے سامنے لڑائی میں صف آرا ہو تو پھر کسی حال
میں بھی انہیں چیچے نہ دکھاؤ اور جو شخص ایسے مقابلہ میں بیٹھے دکھائے گا سوائے اس کے کہ وہ کسی
جنگی تدبیر کے طور پر ادھر ادھر جگہ بدلنے کا طریق اختیار کرے یا مومنوں کی کسی دوسری
پارٹی کے ساتھ ملاپ پیدا کر کے دشمن کا مقابلہ کرنا چاہے تو وہ خدا کے غضب کو اپنے سر پر لے
گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے.“
آج بظاہر ترقی یافتہ زمانہ میں بھی کوئی آزمودہ کار جرنیل اپنی فوج کو اس سے بہتر
ہدایت نہیں دے سکتا.ساتویں اور آخری بات اس حدیث میں بے گناہ مومن عورتوں پر بہتان لگانا بیان کی
گئی ہے اور یہ بات بھی حقیقتا قومی اخلاق کو سخت صدمہ پہنچانے والی ہے مگر افسوس ہے کہ
بے شمار لوگوں میں یہ کمزوری پائی جاتی ہے کہ وہ بہتان والی باتوں کو شوق اور دلچسپی سے سنتے اور
پھر انہیں اس طرح ہو ا دیتے ہیں کہ وہ جنگل کی آگ کی طرح پھیلتی اور معصوم دلوں کو تباہ کرتی
چلی جاتی ہیں حالانکہ اگر غور کیا جائے تو بعض لحاظ سے اصل بے حیائی کی نسبت بھی بے حیائی کا
چر چا سوسائٹی کے لئے زیادہ مضر ثابت ہوتا ہے کیونکہ اس کے نتیجہ میں کمزور لوگوں کے دل
مسموم ہوتے ہیں اور بدی کا رعب مٹتا ہے.بے حیائی کا فعل اگر اس کا علم صرف دو انسانوں تک
محمد و د ر ہے تو باوجود ایک انتہائی گناہ ہونے کے بہر حال اپنے اثرات کے لحاظ سے محدود ہو تا
الانفال: 16
1
Page 117
105
ہے لیکن جب اس کا چرچالوگوں کی زبانوں پر ہونے لگے تو کئی کمزور نوجوان اس کے گندے اثر
سے متاثر ہونے لگتے ہیں اور بدی کا وہ قدرتی رعب جو فطرت انسانی کا حصہ اور بدی کو روکنے کا ایک
زبر دست آلہ ہے کمزور پڑنا شروع ہو جاتا ہے اس لئے اسلام نے جہاں اصل بدی کو روکا ہے وہاں
اس نے بہتان تراشی اور بدی کے چرچے کا رستہ بھی بڑی سختی کے ساتھ بند کیا ہے اور یہی وہ حکمت
کی راہ ہے جو قوم کی حقیقی اصلاح کی موجب ہو سکتی ہے.پھر اگر اخلاق و اطوار کے مختلف پہلوؤں کے لحاظ سے اس حدیث پر نظر ڈالی جائے تو
اس حدیث کی ایک اور خوبی بھی نمایاں ہو کر سامنے آتی ہے اور وہ یہ کہ اس حدیث میں ایمانیات
اور اخلاقیات اور قیام امن اور اقتصادیات اور کمزوروں کے حقوق کی حفاظت اور قومی بقاء اور
بے حیائی کے انسداد کو نہایت لطیف رنگ میں مد نظر رکھا گیا ہے مثلاً شرک سے اجتناب کرنے کا
ذکر ایمان کی حفاظت کی غرض سے داخل کیا گیا ہے.سحر کی حرمت کو کیریکٹر کی بلندی اور
عادات کی صفائی کے پیش نظر شامل کیا گیا ہے.قتل ناحق کے ذکر کو امن عامہ کی غرض سے داخل
کیا گیا ہے.سود کی حرمت کو اقتصادی اصلاح کی بنا پر شامل کیا گیا ہے.یتیم کی حفاظت کے حکم کو
کمزوروں کے ساتھ عدل و انصاف کے قیام کی غرض سے داخل کیا گیا ہے اور بہتان تراشی کی
حرمت کو بے حیائی کے سد باب کے لئے داخل کیا گیا ہے.اس طرح ہمارے آقا صلی الیم نے
ہمارے لئے در حقیقت اس زریں ہدایت کے ذریعہ دریا کو کوزے میں بند کر کے محفوظ کر دیا ہے.
Page 118
106
24
نشہ پیدا کرنے والی چیزوں
کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے
عن جابر بن عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم ما أَشكر
كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ
(سنن أبي داود كتاب الاشربہ باب ما جاء في السكر )
ترجمہ : جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی السلام فرماتے تھے کہ
جس چیز کی زیادہ مقدار نشہ پیدا کرتی ہو اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے.تشریح یہ لطیف حدیث جہاں شراب اور ہر دوسری نشہ آور چیز کو حرام قرار دیتی
ہے وہاں اس حدیث میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جب تک ایک بدی کو اس کی جڑھ سے نہ کاٹا
جائے اور اس کے تمام امکانی رخنوں کو بند نہ کیا جائے اس کا سد باب ممکن نہیں ہو تا.اس لئے
یہ خیال کرنا کہ چونکہ شراب یا دوسری مسکرات کی تھوڑی مقدار نشہ پیدا نہیں کرتی لہذا ان
کے محدود استعمال میں حرج نہیں ایک خطر ناک غلطی ہے.انسانی فطرت کچھ اس طرح پر واقع
ہوئی ہے کہ جب اسے کسی چیز کی اجازت دی جائے تو پھر وہ اس قسم کے باریک فرقوں کو ملحوظ
نہیں رکھ سکتا کہ مجھے فلاں حد سے آگے نہیں جانا چاہیے.خصوصاً نشہ پیدا کرنے والی چیزوں
Page 119
107
میں یہ خطرہ بہت ہی زیادہ ہوتا ہے کیونکہ اس میدان میں ایک دفعہ قدم رکھنے کے بعد اکثر
انسان آگے بڑھنے سے رک نہیں سکتے اور رتی سے ماشہ اور ماشہ سے تولہ اور تولہ سے چھٹانک
اور چھٹانک سے سیر کی طرف قدم بڑھاتے چلے جاتے ہیں.اس لئے آنحضرت صلی اللہ ہم نے
کمال حکمت سے شراب اور دیگر نشہ آور چیزوں کی تھوڑی مقدار کو بھی حرام قرار دیا ہے تاکہ
اس قسم کی خطر ناک بدیوں کا جڑھ سے استیصال کیا جاسکے.دنیا میں لاکھوں انسان محض اس وجہ
سے تباہ ہوئے ہیں کہ انہوں نے شروع شروع میں شراب کے چند قطرے پی کر جسم میں وقتی
گرمی اور دماغ میں عارضی چمک پیدا کرنے کی کوشش کی اور پھر ایسے پھسلے کہ دن رات
مدہوش رہنے لگے.یہی حال افیون اور مارفیا اور بھنگ، چرس وغیرہ کے استعمال کا ہے کہ ان
چیزوں کا تھوڑا تھوڑا استعمال بالآخر زیادہ استعمال کی طرف دھکیلتا ہے اور ساحل سمندر کے
پایاب پانی میں کھیلنے والا انسان آخر کار غرقاب پانی میں پہنچ کر دم توڑ دیتا ہے.اس لئے قرآن
شریف نے شراب اور جوئے کے بعض فوائد کو تسلیم کرنے کے باوجود حکم دیا ہے کہ
اثْمُهُمَا اكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا
یعنی بے شک شراب اور جوئے میں بعض فوائد بھی ہیں لیکن ان کی مضرتوں کا پہلو
ان کے فوائد کے پہلو سے بہت زیادہ بھاری ہے.66
پس سچے مومنوں کو بہر حال ان چیزوں سے پر ہیز کرنا چاہیے.1 : البقرة: 220
Page 120
108
اگر اس جگہ یہ سوال کیا جائے کہ چونکہ استثنائی طور پر بعض ایسے لوگ بھی ہو سکتے
ہیں جو اپنے آپ کو شراب کے قلیل استعمال پر روک سکتے ہیں اور ان کے متعلق اعتدال کی حد
سے تجاوز کرنے کا خطرہ نہیں ہو تا تو کیا ایسے لوگوں کے لئے شراب کا محدود استعمال جائز سمجھا
جائے گا ؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہر گز نہیں بلکہ پھر بھی شراب کا استعمال کسی مسلمان کے
لئے جائز نہیں ہو گا کیونکہ اول تو اس قسم کے قوانین میں اکثریت اور عمومیت کے پہلو کو مد
نظر رکھا جاتا ہے یعنی جب ایک چیز ملک و قوم کے کثیر حصہ کے لئے یقینی طور پر نقصان دہ ہو تو
قانونی عمومیت کے پیش نظر یہ چیز قلیل حصہ کے لئے بھی حرام کر دی جاتی ہے کیونکہ اس کے
بغیر اس قسم کے قوانین قائم نہیں رہ سکتے.دوسرے اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ گو آج ایک
شخص ضبط نفس سے کام لے سکتا ہے مگر کل کو وہ پھسل کر اپنے ضبط کو کھو نہیں بیٹھے گا.تیسرے
اس حدیث میں شراب کی ساری مضر تیں بیان نہیں کی گئیں بلکہ صرف مثال کے طور پر نشہ
یعنی مدہوشی والی مضرت کا ذکر کیا گیا ہے ورنہ شراب کے بعض نقصانات اس کے علاوہ بھی
ہیں.پس اگر بالفرض کسی خاص شخص کے متعلق شراب میں مدہوشی والی مضرت موجود نہ ہو
تو پھر بھی وہ دوسری مضرتوں کی وجہ سے حرام سمجھی جائے گی اور اسی لئے آنحضرت ﷺ نے
اسے ہر صورت میں حرام قرار دیا ہے.خلاصہ کلام یہ کہ اس حدیث میں ہمارے آقا صلی الیم نے ہمیں تین اہم باتوں کی
طرف توجہ دلائی ہے.
Page 121
109
(اول) یہ کہ ہر نشہ پیدا کرنے والی چیز مسلمانوں پر حرام ہے خواہ وہ شراب ہو یا
بھنگ چرس یا افیم ہو یا کوئی اور چیز ہو.(دوم) یہ کہ جس چیز کی زیادہ مقدار نشہ پیدا کرے اس کی تھوڑی مقدار کا استعمال
بھی جائز نہیں ہو گا.اس لئے کوئی شخص یہ بہانہ رکھ کر شراب یا افیم یا بھنگ وغیرہ استعمال نہیں
کر سکتا کہ میں تو صرف ایسی مقدار میں استعمال کرتا ہوں جو نشہ پیدا نہیں کرتی.(سوم) یہ کہ اس قسم کی بدیوں کے سد باب کا صحیح طریق یہ ہے کہ انہیں جڑھ سے
کاٹا جائے اور ان تمام امکانی رخنوں کو بند کیا جائے جہاں سے بدی داخل ہو سکتی ہے کیونکہ اگر
بدی کے داخل ہونے کا راستہ کھلا ہو گا تو لاز مابدی کے داخل ہونے کا امکان بھی قائم رہے گا.
Page 122
110
25
دھوکا باز انسان سچا مسلمان نہیں سمجھا جا سکتا
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ..قَالَ...مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ
(صحیح مسلم کتاب الایـ قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم من غشنا فليس منا)
ترجمہ: ابوہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ جو
شخص تجارت یا دوسرے لین دین میں دھوکا بازی سے کام لیتا ہے اور ظاہر و باطن ایک جیسا
نہیں رکھتا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں.تشریح: یہ ارشاد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا جب کہ آپ نے
ایک غلہ فروش کے ڈھیر کے اندر ہاتھ ڈال کر دیکھا کہ وہ اندر سے گیلا تھا مگر باہر سے خشک غلہ
کی نہ ڈال کر اس نقص کو چھپانے کی کوشش کی گئی تھی.اس وقت آپ کا چہرہ غصہ سے متغیر
ہو گیا اور آپ نے غلہ فروش کو انتہائی ناراضگی کے ساتھ فرمایا کہ یہ دھوکا بازی اسلام میں جائز
نہیں اور جو مسلمان دھوکا کرتا ہے اور خراب مال کو اچھا مال ظاہر کر کے بیچنا چاہتا ہے اس کا
Page 123
111
میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور آپ نے حکم دیا کہ اگر تمہارے مال میں کوئی نقص ہے تو اس
نقص کو ظاہر کرو اور پھر بیچو تاکہ تمہارا خریدار نقص کو مد نظر رکھ کر قیمت کا فیصلہ کر سکے.آپ کی اس انتہائی تاکید کا یہ نتیجہ تھا کہ بعض اوقات صحابہ میں اس قسم کا دلچسپ
اختلاف ہو جاتا ہے کہ مثلاً بیچنے والا اپنے مال کی قیمت دو سو روپیہ بتاتا تھا مگر خریدار کو اصرار
ہو تا تھا کہ نہیں یہ مال تو تین سو روپے کا ہے مگر افسوس ہے کہ آج کل کئی مسلمان کہلانے
والے لوگ تجارت میں بے دریغ دھوکا کرتے ، قسمیں کھا کھا کر جھوٹ بولتے اور کھانے پینے
کی چیزوں میں اس طرح ملاوٹ ملاتے ہیں کہ شاید شیطان بھی شرم سے منہ چھپاتا ہو گا بلکہ
بعض مسلمان تو حج بھی صرف اس خیال سے کرتے ہیں کہ حاجی کہلانے سے ان کی تجارت کو
زیادہ فروغ حاصل ہو جائے گا.میں ہر گز یہ نہیں کہتا کہ سب ایسے ہیں لیکن جہاں قوم کا ایک
معتد بہ حصہ اس قسم کی اخلاقی پستی میں مبتلا ہو وہاں ایسی قوم بدنامی کے داغ سے ہر گز بچ نہیں
سکتی اور بہر حال ہمارے مقدس رسول (فداہ نفسی) کا سچا متبع وہی سمجھا جاسکتا ہے جو آپ کے
حکم کو مان کر ہر قسم کے دھوکے اور فریب سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہے ورنہ وہ اس وعید کی زد
سے بچ نہیں سکتا کہ مَنْ غَشّ فَلَيْسَ مِلی.
Page 124
112
56
دوسری قوموں کی مشابہت اختیار نہ کرو
عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ
اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ
منهم
سنن أبي داود كتاب اللباس باب في لبس الشهرة)
ترجمہ : عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی ا یکم فرماتے
تھے کہ جو شخص ( اپنی ملت اور قوم کا طریق چھوڑ کر ) کسی دوسری قوم کی مشابہت اختیار کرتا
ہے وہ اسی قوم میں سے سمجھا جائے گا.تشریح: یہ مختصر سی حدیث ایک نہایت لطیف نفسیاتی نکتہ پر مشتمل ہے اور اس سے
مراد یہ ہے کہ جو شخص اپنی قوم کے طور و طریق اور اپنی قوم کے شعار کو چھوڑ کر کسی دوسری
قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے اس کے متعلق یہی سمجھا جائے گا کہ اس کا دل اس دوسری قوم
کے طور و طریق اور اس کے شعار سے متاثر ہو کر اس کی ذہنی غلامی اختیار کر چکا ہے کیونکہ اس
قسم کے تشبہ کی خواہش در اصل احساس کمتری کی وجہ سے پید اہوتی ہے یعنی ایک شخص کسی قوم
کے تہذیب و تمدن اور ان کے حالات و خیالات کو بہتر اور ارفع خیال کر کے اپنے آپ کو ان
Page 125
113
کے مقابلہ میں پست اور ادنی سمجھنے لگتا ہے اور پھر ذہنی غلامی میں مبتلا ہو کر اس قوم کی اندھی
تقلید شروع کر دیتا ہے.پس اس میں کیا شک ہے کہ ایسا شخص دراصل اسی قوم میں سے سمجھا
جائے گا جس کی مشابہت وہ اختیار کرتا ہے.لہذا اس لطیف حدیث کے ذریعہ آنحضرت صلی الله علم
نے مسلمانوں کو ہوشیار فرمایا ہے کہ وہ کبھی کسی دوسری قوم کے طریق و تمدن کے نقال نہ بنیں
بلکہ اسلام کے تمدن کو سارے دوسرے تمدنوں سے بہتر اور ارفع خیال کر کے اسلامی شعار
اختیار کریں ورنہ وہ ایک بد ترین قسم کی ذہنی غلامی میں مبتلا ہو کر اپنی ممتاز ہستی اور اپنی ارفع
انفرادیت کو کھو بیٹھیں گے اور اس میں کیا شبہ ہے کہ ذہنی غلامی ظاہری غلامی سے بھی بد تر چیز
ہے.ایک ظاہری غلام بے شک دوسرے شخص کا مملوک ہو تا ہے مگر باوجو د اس کے ،اس کے
دل و دماغ آزاد ہوتے ہیں لیکن ذہنی غلامی میں مبتلا ہونے والا شخص بظاہر آزاد ہونے کے باوجود
اپنے دل و دماغ کی ساری آزادی کھو بیٹھتا ہے اور اس کے اعمال اس بندر کے اعمال سے بہتر
نہیں ہوتے جو محض نقالی جانتا اور دوسروں کے نچانے پر ناچتا ہے.مگر افسوس ہے کہ اپنے آقا صلی الی یم کی اس حکیمانہ تعلیم کے باوجود آج کل کے
مسلمانوں نے مغربی ممالک کی بدترین غلامی اختیار کررکھی ہے.ہندوستان میں انگریز آیا تو
مسلمانوں کے ایک معتدبہ حصے نے اس کی تہذیب و تمدن کے سامنے گھٹنے ٹیک کر اس کے
رنگ میں رنگین ہو نا شروع کر دیا.مسلمانوں کی ڈاڑھیاں غائب ہو گئیں.ان کے لباس کوٹ
پتلون اور ٹائی کالر کے سامنے پسپا ہو گئے.ان کی دعوتوں میں شراب کے جام چلنے لگے اور ان
Page 126
114
کی عور تیں زینت کے لباس پہن کر بازاروں میں نکل آئیں.کیا یہ سب کچھ مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ
فَهُوَ مِنْهُمُ کی بدترین مثال نہیں ؟ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَار
بے شک یہ درست ہے کہ ایک فی الواقع اچھی اور مفید چیز کو اچھے رنگ میں لے
لینے میں کوئی ہرج نہیں.چنانچہ خود ہمارے آقا محمد صلی اللہ یکم فرماتے ہیں کہ
الكَلِمَةُ الْحِكْمَة ضَالَةُ الْمُؤْمِن عَيْها وَجَدَهَا فَهُوَ أَحَقُ بها
یعنی حکمت اور خوبی کی بات مومن کی اپنی ہی کھوئی ہوئی چیز ہوتی ہے.اسے چاہیے
کہ جہاں بھی ایسی چیز پائے اسے لے لے کیونکہ وہ اس کی اپنی ہی چیز ہے.مگر اس کا یہ مطلب
ہر گز نہیں ہے کہ ہر رطب و یابس چیز کو اندھے طور پر اختیار کرناشروع کر دیا جائے بلکہ کسی چیز
کے اختیار کرنے کے لئے دو شرطیں ضروری ہیں.(۱) ایک یہ کہ وہ فی الواقع اچھی ہو اور اسلامی تعلیم اور اسلامی شعار کے خلاف نہ ہو.(۲) دوسرے یہ کہ اسے غلامانہ ذہنیت کے ساتھ اندھے طریق پر اختیار نہ کیا جائے
بلکہ پر کھ کر اور کھوٹا کھر ادیکھ کر علی وجہ البصیرت لیا جائے.1 : ابن ماجہ کتاب الزھد باب الحكمة
Page 127
115
27
دل ٹھیک ہو
تو سارے اعضاء خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں
مَن عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْن بَهِيرٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ
اللهِ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ...أَلَا وَإِنَّ فِي الجَسَدِ مُضْغَةً: إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُهُ
وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ القَلْبُ.(صحیح البخاری کتاب الایمان باب فضل من استبر الدينه)
ترجمہ : نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی یہ تم کو یہ
فرماتے ہوئے سنا ہے کہ انسان کے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے کہ جب وہ اچھا ہو جائے تو
تمام جسم اچھا ہو جاتا ہے اور جب وہ خراب ہو جائے تو تمام جسم خراب ہو جاتا ہے اور اے
مسلمانو ! ہوشیار ہو کر سن لو کہ وہ دل ہے.تشریح : اس حدیث میں نفس کی اصلاح کا لطیف فلسفہ بیان کیا گیا ہے اور وہ یہ کہ
انسان کے تمام اعمال کا منبع اس کا دل ہے اگر انسان کے دل میں نیک اور پاکیزہ جذبات ہوں گے
تو اس کے سارے اعمال لاز ما نیکی کے رستہ پر چلیں گے لیکن اگر دل کے جذبات ناپاک اور
Page 128
116
گندے ہوں گے تو اعمال بھی لا محالہ گندے رستہ پر پڑ جائیں گے کیونکہ دل کے جذبات بیج کا
رنگ رکھتے ہیں اور عمل وہ درخت ہے جو اس کے بیج سے پیدا ہو تا ہے.پس اصلاح کے لئے
اصل فکر دل کی ہونی چاہیے.اگر قوم کے لیڈر اور ملک کے اخبارات عوام الناس کے دلوں میں
اور کالجوں کے پروفیسر ز اور سکولوں کے اساتذہ طلباء کے دلوں میں اور والدین اپنے بچوں کے
دلوں میں نیک جذبات پیدا کر دیں اور ان میں خدا کی محبت اور رسول کی محبت اور دین کی محبت
کے ساتھ ساتھ قوم کے درد اور خدمت اور قربانی اور صداقت اور دیانت کا بیج بو دیں تو پھر
نیک اعمال کے لئے علیحدہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں بلکہ دل کا تقویٰ خود بخود عمل صالح کا
درخت اگانا شروع کر دے گا لیکن اگر دل خراب ہے تو پھر عمل کا درخت اوّل تو اُگے گا ہی
نہیں اور اگر اُگے گا تو فوراہی ٹھٹھر کر ختم ہو جائے گا.حضرت مسیح موعود بانی سلسلہ احمدیہ نے کیا خوب فرمایا ہے کہ
ہر اک نیکی کی جڑ یہ انتقا ہے اگر یہ جڑ رہی سب کچھ رہا ہے!
حق یہی ہے کہ انسان کا دل اس کے تمام نیک اعمال کا منبع اور مولد ہے.اگر دل ٹھیک ہو تو ہاتھ
اور پاؤں اور زبان اور آنکھ کے اعمال خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن اگر دل گندہ ہو تو انسان
کے ہر عمل میں گندگی اور نجاست کی بو پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے.ایسا انسان اگر بظاہر نیک
عمل بجالاتا بھی ہو تو اس کے اعمال میں خشک نقالی یا منافقانہ ریا کے سوا کچھ حقیقت نہیں ہوتی.: در ثمین (اردو)، بشیر احمد شریف احمد اور مبارکہ کی آمین
Page 129
117
پس ہر مصلح کا فرض ہے کہ وہ سب سے پہلے دل کی فکر کرے کیونکہ دل جڑھ کا قائم مقام ہے
اور گندی جڑھ سے کبھی پاک درخت پیدا نہیں ہو سکتا.
Page 130
118
28
جو بات دل میں کھٹکے اس سے اجتناب کرو
عن وايضةَ بْنِ مَعْبَدٍ قَالَ أَتَيْتُ رَسُول الله صلى الله عَليْهِ وَسَلَّم...يَقُولُ:
يَا وَابِصَةُ اسْتَفْتِ نَفْسَكَ الْبِرُّ مَا اطْمَأَنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ، وَاطْمَأَنَّتُ إِلَيْهِ
النَّفْسُ وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي الْقَلْبِ وَتَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ ، وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ
(مسند احمد بن حنبل ، حديث وابصة بن معبد الاسدی، جلد 7 صفحه 423)
ترجمہ: وابصہ بن معبد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی ا یکم فرماتے تھے
کہ اپنے نفس سے فتوی لو.نیکی وہ ہے جس پر تمہارا دل تسکین محسوس کرے اور تمہارا نفس
اطمینان پا جائے اور گناہ وہ ہے جو تمہارے نفس میں کھٹکے اور تمہارے سینے میں تنگی پیدا کرے
خواہ دوسرے لوگ تمہیں اس کے جائز ہونے کا فتویٰ ہی دیں.تشریح: آنحضرت صلی علی علم کا ارشاد اس ابدی صداقت پر مبنی ہے کہ خدا تعالیٰ نے جو
خالق فطرت ہے ہر انسان کو پاک فطرت عطا کی ہے اور یہ صرف بعد کے حالات ہیں جو اسے
غلط رستہ پر ڈال کر اس کی پاک فطرت کو ناپاک پردوں میں چھپا دیتے ہیں لیکن پھر بھی فطرت
کی نیکی اور ضمیر کی روشنی بالکل مردہ نہیں ہوتی اور زندگی بھر انسان کے لئے شمع ہدایت کا کام
Page 131
119
دیتی ہے حتی کہ بعض اوقات دنیا کے گندوں میں پھنسے ہوئے لوگ بھی جب علیحدہ بیٹھ کر اپنی
حالت پر غور کرتے ہیں تو ان کی فطرت دنیا داری کے پردوں سے باہر آکر انہیں ملامت شروع
کر دیتی ہے.آنحضرت صلی اللہ ﷺ کا یہ مبارک ارشاد جو اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے اسی فطری
نور کی بنیاد پر قائم ہے.فرماتے ہیں کہ عام اصولی امور میں ایک عقل مند منتقی انسان کے لئے
کسی خارجی مفتی کی ضرورت نہیں کیونکہ خود اس کا اپنا دل اس کے لئے مفتی کی حیثیت رکھتا
ہے.اسے چاہیے کہ نیکی اور بدی کے متعلق اپنے دل سے فتویٰ پوچھے اور اپنے ضمیر کے نور
سے روشنی کا طالب ہو کیونکہ نیکی دل میں شرح صدر اور تسکین اور اطمینان کی کیفیت پیدا کرتی
ہے اور بدی سینہ میں کھٹکتی اور دل میں چھتی اور نفس پر ایک بوجھ بن کر بیٹھ جاتی ہے.ایسی
صورت میں دوسروں کے فتووں سے جھوٹا سہارا تلاش کرنا بے سود ہے بلکہ انسان کو اپنے ضمیر
کی آواز پر کان دھر نا چاہیے اور اگر کسی بات پر ضمیر رکتا اور دل کی تنگی محسوس کرتا ہے تو انسان
کو چاہیے کہ مفتیوں کے فتوے کے باوجود ایسے کام سے رک جائے اور نور ضمیر کے فتویٰ کو قبول
کرے جو خالق فطرت کی پیدا کی ہوئی ہدایت ہے.لیکن جیسا کہ آنحضرت صلی الل ہم نے استفت نَفْسَكَ (اپنے نفس سے فتویٰ پوچھ )
کے الفاظ میں اشارہ فرمایا ہے ضروری ہے کہ دل کا فتویٰ لینے کے لئے انسان دوسروں سے علیحدہ
ہو کر خلوت میں سوچے اور تقویٰ کو مد نظر رکھ کر اپنے دل کا فتویٰ لے ورنہ دوسروں کی رائے
اس کی ضمیر پر غالب آکر اس کی شمع فطرت پر پردہ ڈال دے گی لیکن اگر وہ علیحدگی میں بیٹھ کر
اور تمام خارجی اثرات سے الگ ہو کر اپنے دل سے فتویٰ پوچھے گا تو اس کے دل کی فطری روشنی
Page 132
120
اس کے لئے ایسی شمع ہدایت مہیا کر دے گی جسے ازل سے نیکی بدی میں امتیاز کرنے کی طاقت
حاصل ہو چکی ہے اور اگر غور کیا جائے تو یہ نیکی بدی کا فطری شعور خدا کی ہستی پر بھی ایک
بھاری دلیل ہے کیونکہ اگر نعوذ باللہ خدا کوئی نہیں تو یہ نیکی بدی کا فطری شعور جو انسان کی دل
کی گہرائیوں میں مرکوز ہو کر اس کی ہدایت کا سامان مہیا کر رہا ہے کہاں سے آگیا ہے ؟
Page 133
121
29
احساس کمتری ایک سخت مہلک احساس ہے
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ
هَلَكَ النَّاسُ فَهُوَ أَهْلَكَهُمْ
(صحیح مسلم کتاب البر والصلة باب النهي عن قول هلك الناس)
ترجمہ: ابوہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی ا لم فرماتے تھے کہ
جب کوئی شخص دوسرے لوگوں کے متعلق کہتا ہے کہ وہ ہلاک ہو گئے تو ایسا شخص خود یہ بات
کہہ کر انہیں ہلاک کرتا ہے ( یا یہ کہ ایسا شخص خود ان سے زیادہ ہلاک شدہ ہوتا ہے).تشریح: یہ حدیث ایک عظیم الشان نفسیاتی نکتہ پر مبنی ہے جسے آج کل کی اصطلاح
میں احساس کمتری (انفیری آریٹی کا مپلکس) یا شکست خوردہ ذہنیت (ڈیفی ٹسٹ ٹنڈ نسی) کا نام
دیا جاتا ہے.آنحضرت لیلی لی یکم فرماتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں امید و رجا اور خود اعتمادی
اور عزت نفس کے جذبات کو بیدار کر کے اوپر اٹھانے اور بلند کرنے کی کوشش کرونہ کہ
احساس کمتری اور شکست خوردہ ذہنیت کے ذریعہ مایوسی اور پست ہمتی پیدا کر کے انہیں قعر
مذلت میں گرانے کا رستہ کھولو.جو شخص لوگوں کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں اور کمزوریوں پر واویلا
Page 134
122
شروع کر دیتا ہے کہ یہ لوگ تو مر گئے اور تباہ ہو گئے اور خود اس بات کے کہنے سے ان کے
دلوں میں مایوسی اور احساس کمتری پیدا کر کے ان کی تباہی کا رستہ کھولتا ہے.پس آنحضرت
صلی ای ایم نے کمال حکمت سے ہدایت فرمائی کہ بے شک غلطیوں پر مناسب تادیب اور اصلاح کا
طریق اختیار کرو مگر بات بات پر شور مچانا کہ فلاں لوگ اپنی بد عملی میں تباہی کی حد کو پہنچ گئے
ہیں خود اپنے ہاتھ سے ان کی تباہی کا بیج بونا ہے جس سے ہر دانا مصلح کو پر ہیز کرنا چاہیے.اس معاملہ میں ہمارے آقاصلی این یکم کا اپنا مبارک اسوہ یہ تھا کہ جب ایک دفعہ صحابہ کی
ایک پارٹی جسے آنحضرت صلی اللہ ہم نے کسی جنگی مہم پر بھیجا تھا میدان جنگ سے بھاگ کر مدینہ
واپس پہنچ گئی تو اس خیال سے کہ اسلام میں دشمن کے سامنے سے بھاگنا حرام ہے ان پر ایسی
شرم اور ندامت غالب تھی کہ وہ آنحضرت صلیالی نیلم کے سامنے نہیں آتے تھے.جب آپ نے
انہیں مسجد کے ایک کونہ میں منہ چھپا کر بیٹھے ہوئے دیکھا تو آپ ان کی طرف گئے اور انہیں
آواز دے کر پکارا کہ تم کون لوگ ہو ؟ انہوں نے شرم کی وجہ سے آنکھیں نیچے کئے ہوئے
عرض کیا کہ نَحْنُ الْفَرَّارُونَ "یار سول اللہ ہم بھگوڑے ہیں.آپ نے ان کی شکست خوردہ
ذہنیت کو بھانپ کر فوراجواب دیا کہ بَلْ أَنْتُمُ الْعَذَارُونَ وَانَا فِقتُكُمْ یعنی نہیں نہیں
تم بھگوڑے نہیں ہو تم تو زیادہ زور سے حملہ کرنے کے لئے پیچھے ہٹے تھے اور تم کسی غیر کے
پاس نہیں گئے بلکہ میرے پاس آئے ہو جو تمہارا قائد بن کر تمہیں پھر میدان جنگ میں لے
جانے والا ہوں“.پستی میں لڑھکتے ہوئے اور احساس کمتری کی لہروں میں تھیڑے کھاتے
1 : ترمذی ابواب الجهاد باب ما جاء فى الفرار من الزحف
Page 135
123
ہوئے نوجوانوں کے کانوں میں آپ کی یہ روح پرور آواز پہنچی اور وہ ایک جست کے ساتھ
آگے بڑھے اور آپ کے دست مبارک کو اپنے ہاتھوں میں لے کر خوشی سے چومنے لگ گئے.یہ وہ درس حکمت ہے جو ہمارے آقا ( فداہ نفسی) نے اپنے صحابہ کو عملاً دیا اور جس کی آپ نے
اوپر کی حدیث کے ذریعہ قولاً تلقین فرمائی.اللهم صل على محمد وبارك وسلم
اس حدیث میں جو اهْلَكَهُمُ کا لفظ آتا ہے یعنی ایسا شخص خود انہیں ہلاک کرنے
والا ہے.اس کے دوسرے معنی اعراب کی خفیف تبدیلی کے ساتھ (یعنی کاف کی پیش سے )
یہ بھی ہیں کہ وہ خود سب سے زیادہ ہلاک شدہ ہے“.اور ظاہر ہے کہ اس معنی کے لحاظ سے
بھی یہ حدیث نہایت لطیف مفہوم کی حامل قرار پاتی ہے کیونکہ اس صورت میں اس کا مطلب
یہ ہو گا کہ ایسا شخص جو دوسروں کو ہلاک شدہ قرار دیتا ہے وہ دراصل خود سب سے زیادہ
شکست خوردہ ذہنیت میں مبتلا ہے.پس خواہ دوسرے لوگ ہلاک شدہ ہوں یا نہ ہوں وہ یہ الفاظ
کہہ کر اپنی ہلاکت پر ضرور مہر لگا لیتا ہے.
Page 136
124
30
سچی توبہ گناہ کو مٹادیتی ہے
عنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ القَانِبُ من اللذي كَمَن لا ذَلبَ لَهُ.(سنن ابن ماجه کتاب الزهد باب ذكر التوبة)
ترجمہ: ابو عبیدہ بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ
صلى الم فرماتے تھے کہ گناہ سے توبہ کرنے والا شخص ایسا ہو تا ہے کہ گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں.تشریح تو بہ کا فلسفہ نہ صرف انسان کی روحانیت پر بلکہ اس کے اخلاق پر بھی نہایت
گہرا اثر رکھتا ہے.تو بہ کے ذریعہ انسان خدا کی طرف سے پر امید رہتا ہے اور اپنے اخلاق میں
زیادہ بلندی اختیار کر سکتا ہے مگر افسوس ہے کہ اسلام کے سوا اکثر مذاہب نے انسان پر تو بہ کا
دروازہ بند قرار دے کر اس کے اندر ایک طرف خدا کے متعلق بدگمانی اور دوسری طرف
مایوسی اور اخلاقی پستی کا دروازہ کھولا ہے.چنانچہ مسیحیت نے توبہ کا دروازہ بند کر کے ایک سراسر
مصنوعی اور غیر فطری عقیدہ یعنی کفارہ میں پناہلی ہے اور ہندو مذہب نے اپنے متبعین کو اواگون
Page 137
125
یعنی تناسخ کی دلدل میں پھنسا رکھا ہے حالانکہ تو بہ کا مسئلہ ایک بالکل فطری مسئلہ ہے جس کے
بغیر نہ تو انسان کی روحانیت مکمل ہوتی ہے اور نہ ہی اس کے اخلاق کمال حاصل کر سکتے ہیں.پھر تعجب یہ ہے کہ توبہ کا دروازہ بند کرنے والے مذاہب اس دنیا کے خالق و مالک خدا
میں وہ اچھے اخلاق بھی تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں جو ایک نیک انسان میں قابل تعریف سمجھے
جاتے ہیں.ایک شریف انسان ہر روز اپنے بچوں اور اپنے دوستوں اور اپنے ماتحتوں اور اپنے
نوکروں کی غلطیاں معاف کرتا ہے اور اس کے اس فعل کو قابل تعریف سمجھا جاتا ہے لیکن
افسوس ہے کہ خدا کے لئے اس کریمانہ خلق کو ناجائز خیال کیا گیا ہے اور ضروری سمجھا جاتا ہے کہ
جب کوئی انسان خدا کا کوئی گناہ کرے تو پھر خواہ اس کے بعد وہ کیسا ہی نادم اور تائب ہو خدا کو اسے
کچل کر رکھ دینا چاہیے.اسلام اس گندے نظریے کو دور سے ہی دھکے دیتا ہے اور ہر بچے تو بہ کنندہ
کے لئے خدائی مغفرت اور رحمت کا دروازہ کھولتا ہے اور اس طرح خالق و مخلوق کے درمیان ایک
طرف سے شفقت ورحمت کی اور دوسری طرف سے انابت و امتنان کی ایسی نہر جاری کر دیتا ہے جو
خدا کی خدائی اور بندے کی بندگی کے شایان شان ہے.ظاہر ہے کہ انسان کمزور ہے اور بسا اوقات
وقتی اثرات کے ماتحت لغزش کھا جاتا ہے تو اس صورت میں یہ کتنا ظلم ہے کہ اگر وہ بعد میں سچے
دل سے نادم اور تائب ہو تو پھر بھی اسے کشتی اور گردن زدنی قرار دیا جائے.یہ خیال کرنا کہ توبہ قبول کرنے سے گناہ پر جرات پیدا ہوتی ہے بالکل موہوم اور
باطل خیال ہے.سچی توبہ تو انسان کو پاک کرنے کا ذریعہ ہے نہ کہ گناہ پر دلیر کرنے کا موجب
کیونکہ اسلام نے سچی توبہ کے لئے ایسی شرطیں لگادی ہیں جو تو بہ کو ایک بھاری انقلاب اور حقیقی
Page 138
126
قلب ماہیت کا رنگ دے دیتی ہیں اور جیسا کہ قرآن شریف اور حدیث سے ثابت ہوتا ہے یہ
شرطیں تین ہیں.(۱) یہ کہ توبہ کرنے والا اپنی غلطی اور گناہ پر سچے دل سے ندامت محسوس کرے اور
صمیم قلب سے معافی اور مغفرت کا طالب ہو.(۲) یہ کہ وہ آئندہ کے لئے اس غلطی اور گناہ سے مجتنب رہنے کا عہد کرے اور اس
کے لئے خدا سے توفیق مانگے.(۳) یہ کہ اگر اس کی غلطی اور گناہ کی عملی تلافی ممکن ہے تو وہ اس کی تلافی کرے
مثلاً اگر اس نے کسی شخص کا مال غصب کیا ہوا ہے تو وہ اسے واپس کرے یا کسی کا حق دبایا ہوا ہے
تو اسے بحال کرے.ان شرائط کے ساتھ کون عقل مند انسان تو بہ کو قابل اعتراض خیال کر سکتا ہے ؟ حق یہ
ہے کہ سچی توبہ ایک موت ہے جو انسان کو نئی زندگی بخشتی اور خدا کی رحمت اور شفقت اور مغفرت
کا رستہ کھولتی ہے اور یہ صرف اسلام ہی ہے جو انسان کے لئے سچی توبہ کا دروازہ کھولتا ہے.☆☆☆
Page 139
127
31
مومن ایک سوراخ سے دو دفعہ نہیں کاٹا جاتا
عن أبي هرير رضى اللهُ عَنْهُ عَنِ اللَّين صلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: لا يُلدغ
الْمُؤْمِنُ مِنْ مُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ -
(صحيح البخاري كتاب الادب باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين)
ترجمہ: ابوہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی ا لم فرماتے تھے کہ
مومن ایک سوراخ سے دو دفعہ نہیں کاٹا جاتا.تشریح : یہ لطیف حدیث بڑے وسیع مفہوم پر مشتمل ہے.اس کے صاف اور
سیدھے معنی تو یہ ہیں کہ سچا مومن ہمیشہ ہوشیار اور چوکس رہتا ہے اور اگر وہ کسی سوراخ کے
اندر ہاتھ ڈالتا ہے (یعنی کسی شخص یا پارٹی یا قوم کے ساتھ اس کا واسطہ پڑتا ہے ) اور اس سوراخ
کے اندر سے اسے کوئی چیز کاٹ لیتی ہے تو پھر وہ دوسری دفعہ اس سوراخ میں سے نہیں کاٹا جاتا
یعنی وہ ایک ہی تجربہ کے نتیجہ میں ہوشیار ہو کر مزید نقصان سے بچ جاتا ہے اور دوسرے فریق
کو یہ موقع نہیں دیتا کہ وہ اسے دوبارہ ڈنگ مارے.اس ارشاد کے ذریعہ آنحضرت صلی ا ہم نے
گویا مسلمانوں کو غیر معمولی طور پر ہو شیار اور چوکس رہنے کی تلقین فرمائی ہے اور سچے مومن کی
Page 140
128
یہ علامت بتائی ہے کہ وہ مومنانہ حسن ظنی کی وجہ سے ایک دفعہ نقصان اٹھا جائے تو اٹھا جائے
مگر ایک ہی شخص سے یا ایک ہی معاملہ میں دوبارہ نقصان نہیں اٹھاتا اور ہر تلخ تجربہ سے فائدہ
اٹھا کر اپنی پوزیشن کو مضبوط سے مضبوط تر کرتا ہے اور اپنے لئے ترقی کے ایک دروازہ کے بعد
دوسر ادروازہ کھولتا چلا جاتا ہے.آنحضرت صلی یم کا یہ ارشاد زندگی کے ہر شعبہ سے ایک جیسا تعلق رکھتا ہے مثلاً اگر
کسی مسلمان کو کوئی تاجر ایک دفعہ دھوکا دے تو یہ حدیث مسلمان کو ہو شیار کر رہی ہے کہ دیکھنا
پھر دوسری دفعہ اس بد دیانت تاجر سے دھوکا نہ کھانا اور اگر کوئی پیشہ ور کسی مسلمان کے ساتھ
خیانت کے ساتھ پیش آئے تو یہ حدیث اس مسلمان کو بھی متنبہ کر رہی ہے کہ ایسے خیانت پیشہ
س سے دوسری بار زک نہ اٹھا اور اگر کوئی شخص دوست بن کر مسلمان کو اپنے فریب کا شکار
بنائے تو یہ حدیث اس مسلمان کو بیدار کر رہی ہے کہ پھر کبھی ایسے فریب میں نہ آنا.الغرض
اس حدیث کا دائرہ بہت وسیع ہے بلکہ اگر کوئی شخص کسی چیز کو گناہ نہ خیال کرتے ہوئے اس کا
مر تکب ہوتا ہے یا گناہ تو خیال کرتا ہے مگر اس کے نقصان کی اہمیت نہیں سمجھتا اور صرف تجربہ
کے بعد اس کی مضرت کو محسوس کرتا ہے تو یہ حدیث اس کے لئے بھی ایک شمع ہدایت کا کام
دے رہی ہے کہ اب پھر اس چیز کے قریب نہ جانا ورنہ تم ایک سوراخ سے دو دفعہ کاٹے جاؤ
گے جو ایک مومن کی شان سے بعید ہے.خلاصہ کلام یہ کہ یہ لطیف حدیث ہر مسلمان کو ہوشیار کر رہی ہے کہ دنیا میں چوکس
ہو کر رہو اور ہر ٹھو کر کو اپنے قدموں کی مضبوطی کا موجب بناؤ اور ہر لغزش کے بعد اس طرح
Page 141
129
جست کر کے اٹھو کہ پھر کبھی لغزش نہ آئے اور اس کے بعد بڑھتے چلے جاؤ اور آگے ہی بڑھتے
چلے جاؤ.
Page 142
130
32
اچھے اخلاق سے بہتر کوئی عمل نہیں
عن أَبي الأَرْدَاءِ رَضى الله عنه ، عَنِ النَّبي صلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِن
فى أفقل فى الميزان من حُسْنِ الخلي.(سنن ابی داود کتاب الادب باب فی حسن الخلق)
ترجمہ: ابودرداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی ا ورم فرماتے تھے کہ
خدا کے تول میں کوئی چیز اچھے اخلاق سے زیادہ وزن نہیں رکھتی.تشریح: اعلیٰ اخلاق دین کا آدھا حصہ ہوتا ہے اور اسلام نے اخلاق پر انتہائی زور دیا ہے
حتی کہ اس حدیث میں آنحضرت صلی اللہ یکم فرماتے ہیں کہ اخلاق سے بڑھ کر خدا کے ترازو میں کسی
چیز کا وزن نہیں اور ایک دوسری حدیث میں فرماتے ہیں کہ جو شخص بندوں کا شکر گزار نہیں بنتاوہ
خدا کا بھی شکر گزار نہیں بن سکتا.دراصل اعلیٰ اخلاق ہر نیکی کی بنیاد ہیں حتی کہ روحانیت بھی
در حقیقت اخلاق ہی کا ایک ترقی یافتہ مقام ہے.اسی لئے ہمارے آقا صلی للی کم نے اخلاق کی درستی پر
بہت زور دیا ہے اور اس بارے میں اتنی حدیثیں بیان ہوئی ہیں کہ شمار سے باہر ہیں.
Page 143
131
اس کے علاوہ اسلام نے اعلیٰ اخلاق کے اظہار کے لئے کسی حق دار کے حق کو نظر
انداز نہیں کیا.خدا سے لے کر بندوں تک اور پھر بندوں میں بادشادہ سے لے کر ادنیٰ خادم
تک ہر ایک کے بارے میں حسن خلق کی تاکید فرمائی ہے.افسر ماتحت، باپ بیٹے ، خاوند بیوی،
بہن بھائی ، ہمسایہ اجنبی، دوست دشمن، انسان حیوان ہر ایک کے حقوق مقرر فرمائے ہیں اور
پھر ان حقوق کو بہترین صورت میں ادا کرنے کی ہدایت دی ہے اور کسی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو
بھی نظر انداز نہیں کیا.حتی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے ملنے
والوں کو مسکراتے ہوئے چہرہ سے مل کر ان کے دل کو خوش کرو تو یہ بھی تمہارا ایک نیک خلق
ہو گا اور تمہیں خدا کے حضور ثواب کا مستحق بنائے گا اور دوسری جگہ آپ فرماتے ہیں کہ رستہ
چلتے ہوئے اگر کوئی کانٹے دار چیز یا پاؤں کو پھسلانے والا چھلکا یا ٹھو کر لگانے والا پتھر یا بد بو پیدا
کرنے والی گندی چیز وغیرہ نظر آئے تو اسے رستہ سے ہٹا دو تا کہ تمہارا کوئی بھائی اس کی وجہ سے
تکلیف میں مبتلا نہ ہو.خود آپ کے اخلاق فاضلہ کا یہ حال تھا کہ کبھی کسی سوالی کو رد نہیں کیا.کبھی کسی کا
ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اسے چھوڑنے میں پہل نہیں کی.یتیموں کے سر پر شفقت کا ہاتھ
رکھا.بیواؤں کی دستگیری فرمائی.ہمسایوں کو اپنے حسن سلوک سے گرویدہ کیا.چھوٹے سے
چھوٹے صحابی کی بیماری کا سنا تو اس کی عیادت کو تشریف لے گئے اور اس سے شفقت اور محبت کا
1 : ترمذی کتاب البر والصلة باب ما جاء فی طلاقة الوجہ
2 : مسلم کتاب الزكاة باب بيان ان اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف
Page 144
132
کلام کر کے اس کی ہمت بڑھائی.مدینہ میں ایک غریب بوڑھی عورت رہتی تھی جو ثواب کی
خاطر مسجد نبوی میں جھاڑو دیا کرتی تھی.وہ چند دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر نہیں
آئی تو آپ نے صحابہ سے دریافت فرمایا کہ فلاں عورت خیریت سے تو ہے ؟ صحابہ نے عرض
کیا.یارسول اللہ !وہ بیچاری تو مختصر سے بیماری کے بعد فوت ہو گئی اور ہم نے آپ کی تکلیف کے
خیال سے آپ کو اس کے جنازہ کی اطلاع نہیں دی.آپ خفا ہوئے کہ مجھے کیوں بے خبر رکھا
اور پھر اس کی قبر پر جاکر دعا فرمائی.ایک دفعہ غالباً پردہ کے احکام سے پہلے جب کہ آپ اپنی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ
کے پاس تشریف رکھتے تھے ایک شخص آپ سے ملنے کے لئے آیا.آپ نے اس کی اطلاع پا کر
حضرت عائشہ سے فرمایا.یہ آدمی اچھا نہیں ہے مگر جب یہ شخص آپ کے پاس آیا تو آپ نے
بڑی دلداری اور شفقت کے ساتھ اس سے گفتگو فرمائی.جب وہ چلا گیا تو حضرت عائشہ نے
آپ سے عرض کیا کہ یارسول اللہ ! آپ اس شخص کو برا کہتے تھے مگر جب وہ آپ سے ملا تو آپ
نے بڑی دلداری اور شفقت کے ساتھ اس سے باتیں کیں ؟ آپ نے فرمایا.عائشہ ! کیا میر ایہ
فرض نہیں کہ لوگوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آؤں 2 ؟ ابو سفیان اسلام لانے سے پہلے
آنحضرت صلی اللہ کی کا بد ترین دشمن تھا مگر جب قیصر رومانے اس سے پوچھا کہ محمد (صلی للی ) لوگوں
کو کیا تعلیم دیتا ہے اور کیا اس نے کبھی تمہارے ساتھ کوئی بد عہدی یا غداری کی ہے ؟ تو
1 : بخاری کتاب الجنائز باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن
2 : بخاری کتاب الادب باب لم يكن نبي الله فاحشا.
Page 145
133
ابو سفیان کی زبان سے اس کے سوا کوئی الفاظ نہ نکل سکے کہ وہ بت پرستی سے روکتا ہے اور حسن
اخلاق کی تعلیم دیتا ہے اور اس نے آج تک ہمارے ساتھ کوئی بد عہدی نہیں کی.آپ کے یہ اخلاق فاضلہ صرف انسانوں تک ہی محدود نہیں تھے بلکہ آپ نے بے
زبان جانوروں تک کو بھی اپنی شفقت میں شامل فرمایا چنانچہ آپ اپنے صحابہ کو ہمیشہ تاکید
فرماتے تھے کہ فِي كُل كبد رطبة أجره یعنی یا درکھو کہ ہر جاندار چیز پر رحم کرنا ثواب کا
موجب ہے.“ ایک موقع پر ایک اونٹ جس پر زیادہ بوجھ لاد دیا گیا تھا تکلیف سے کراہ رہا تھا.آپ اسے دیکھ کر بے قرار ہو گئے اور اس کے قریب جا کر اس کے سر پر محبت کے ساتھ ہاتھ
پھیرا اور اس کے مالک سے کہا بے زبان جانور تمہارے ظلم کی شکایت کر رہا ہے.اس پر رحم
کرو تا تم پر بھی آسمان پر رحم کیا جائے.یہ وہ اخلاق ہیں جو ہمارے آقا نے ہمیں سکھائے مگر افسوس ہے کہ آج کل بہت سے
مسلمان ان اخلاق کو فراموش کر چکے ہیں.1
: بخاری ، کتاب بدء الوحي باب كيف كان بدء الوحى
2 : بخاری کتاب المساقاة باب فضل سقى الماء
3 : ابوداؤد کتاب الجھاد باب مایو مر به من القيام على الدوائب و البهائم
Page 146
134
33
دوسری قوموں کے معزز لوگوں کا احترام کرو
عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَاكُمْ كَرِيمُ
قَوْمٍ فَأَكْرِمُوهُ
(سنن ابن ماجه کتاب الادب باب اذا اتاکم کریم قوم فاکر موه)
ترجمہ: عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی علیکم فرمایا کرتے
تھے کہ جب تمہارے پاس کسی قوم کا بڑا آدمی آئے تو اس کا واجبی احترام کیا کرو.تشریح: ملکوں اور قوموں اور پارٹیوں کے تعلقات کو استوار رکھنے کا بہترین ذریعہ
ایک دوسرے کے لیڈروں کا اکرام و احترام ہے.ہمارے آقا صلی الیکم نے اس بارے میں بھی
مسلمانوں کو سخت تاکید فرمائی ہے.چنانچہ یہ حدیث جو اسی قسم کی دوسری بہت سی حدیثوں میں
سے بطور نمونہ لی گئی ہے اس سنہری ارشاد کی حامل ہے.اختلافات جس طرح افراد کے
درمیان ہو جاتے ہیں اسی طرح قوموں اور ملکوں کے درمیان بھی اختلافات ہوتے رہتے ہیں
مگر ان اختلافات کے زہر کو کم کرنے کا بہترین ذریعہ ایک دوسرے سے حسن اخلاق سے پیش
آنا ہے اور اس تعلق میں دوسری قوموں اور پارٹیوں کے لیڈروں کا واجبی احترام کرنا بڑا بھاری
Page 147
135
اثر رکھتا ہے.لہذا آنحضرت صلی یک کمار شاد فرماتے ہیں کہ جب بھی تمہارے پاس کسی قوم یا
پارٹی کا کوئی رئیس یا لیڈر آئے تو خواہ وہ کسی مذہب وملت کا ہو اس کے ساتھ واجبی احترام سے
پیش آؤ اور اس کے خاطر خواہ اکرام میں ہر گز غفلت سے کام نہ لو.اس زریں ہدایت میں
مہمان نوازی اور حسن اخلاق اور حسن سیاست تینوں صفات حسنہ کا بہترین خمیر ہے.اس بارے میں آنحضرت صلی اللہ کی کا ذاتی اسوہ یہ تھا کہ باوجود اس کے کہ آپ نہایت
درجہ سادہ مزاج تھے اور لباس اور خوراک میں کوئی تکلف کا پہلو نہیں تھا مگر آپ نے بیرونی
قوموں کے وفدوں کے استقبال کے لئے خاص لباس رکھا ہوا تھا اور جب بھی کوئی وفد آتا تھا
آپ اس خاص لباس کو پہن کر اس سے ملاقات فرماتے تھے تا کہ آپ باہر سے آنے والے
مہمانوں کا واجبی اکرام کر سکیں اور آپ کو وفود کے اکرام کا اتنا خیال تھا کہ مرض الموت میں
وصیت فرمائی کہ میرے پیچھے وفدوں کے اکرام میں کمی نہ آنے دینا.ایک دفعہ ایک سفیر نے
آپ کے روبرو نہایت گستاخانہ رویہ اختیار کیا.آپ نے فرمایا تم ایک قوم کے سفیر ہو کر آئے
ہو اس لئے میں تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا 2.مکہ فتح ہوا تو آپ نے عام اعلان فرمایا کہ جو شخص
مقابلہ سے دست کش ہو کر اپنے گھر کے اندر بیٹھا ر ہے گا اور دوسروں کے گھروں میں جا جا کر
سازشوں کی سکیمیں نہیں سوچے گا وہ ہماری طرف سے امن میں ہے.اس پر ابو سفیان رئیس
مکہ نے کہا کہ میں قریش کا سردار ہوں میر اکچھ مخصوص اکرام بھی ہونا چاہیے.آپ نے فرمایا.1 : بخاری کتاب الجهاد باب هل يستشفع الى اهل الذمه؟
2 : ابوداؤد كتاب الجهاد باب في الرسل
Page 148
136
بہت اچھا.آپ
کا گھر مستثنیٰ ہے.پس جو شخص اپنے گھر کے اندر بیٹھار ہے گا یا تمہارے گھر میں
پناہ لے گا وہ ہماری پناہ میں ہے'.الغرض آپ نے دوسری قوموں کے لیڈروں کا انتہائی اکرام
کیا اور اپنے صحابہ کو بھی اس کی تاکید فرمائی اور یہی وہ تعلیم ہے جو دنیا میں امن اور دلوں کی
صفائی کا موجب بن سکتی ہے.: ابو داؤد کتاب الخروج باب ما جاء فى خبر مكة
Page 149
137
34
مزدور کو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے
مزدوری دو
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَعْطُوا الْأَجِيرَ
أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقْهُ
(سنن ابن ماجه کتاب الرهون باب أجر الأجراء)
ترجمہ: عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ وسلم فرماتے تھے
کہ مزدور کو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری دیا کرو.تشریح : آنحضرت صلی ایم نے جہاں قوموں کے رئیسوں اور لیڈروں کے واجبی
اکرام کی تاکید فرمائی ہے وہاں غریبوں اور کمزور لوگوں کے حقوق کا بھی پورا پورا خیال رکھا ہے
اور چونکہ مزدور طبقہ عموماً غربت کی انتہائی حالت میں ہوتا ہے اس لئے آپ نے مزدوروں کے
حقوق کی طرف خاص طور پر توجہ دلائی اور ارشاد فرمایا کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے
اُسے اجرت دو.ان حکیمانہ الفاظ میں آپ کی غرض صرف یہی نہیں تھی کہ اجرت کی ادائیگی
میں جلدی کی جائے اور بس بلکہ دراصل ان الفاظ میں مزدوروں اور غریبوں کے حقوق کی
Page 150
138
طرف عمومی توجہ دلانا اصل غرض تھی اور چونکہ اُجرت کی بر وقت ادائیگی مزدور کے حقوق کا
سب سے ادنیٰ حصہ ہوتا ہے اس لئے آپ نے مثال کے طور پر اس ادنی حصہ کا ذکر کر کے
تاکید فرما دی تا کہ ادنی حصہ کی طرف توجہ خود بخود اعلیٰ حصوں کی حفاظت کا موجب بن
جائے.اس میں کیا شبہ ہے کہ جو مصلح اجرت کی ادائیگی کے لئے مزدور کا پسینہ خشک ہونے کی
بھی مہلت نہیں دیتا وہ دراصل ان الفاظ میں یہ بھی بتانا چاہتا ہے کہ مزدور کو اس کی پوری پوری
اجرت دو اور اس کے واجب آرام کا خیال رکھو اور اس پر کوئی ایسا بوجھ نہ ڈالو جو اس کی طاقت
سے باہر ہو.چنانچہ جو تعلیم آپ نے خادموں کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں دی ہے یا
جو ارشاد آپ نے اسلامی اخوت اور اسلامی مساوات کے متعلق فرمایا ہے (جس کی کسی قدر
تفصیل خاکسار مؤلف کی کتاب سیرۃ خاتم النبيين حصہ نمبر ۲ و نمبر ۳ میں بیان کی جاچکی ہے ) وہ
اس بات پر شاہد ہے کہ ہمارے آقا صلی الی یکم غریب طبقہ کے کتنے ہمدرد، کتنے بہی خواہ اور ان کے
حقوق کے کس درجہ محافظ تھے.آپ نے انفرادی جد و جہد کے محرک کو زندہ رکھنے اور ہر شخص کو اس کی ذاتی سعی
کے ثمرہ سے حصہ دینے کے لئے بے شک انفرادی جائیداد کی اجازت مرحمت فرمائی مگر ساتھ
ہی زکوۃ اور حرمت سود اور تقسیم ورثہ وغیرہ کے زریں اصولوں کے ذریعہ دولت کو سموتے
رہنے کی بھی ایک مؤثر مشینری قائم فرما دی اور جو فرق بھی باقی رہ جائے اس کے متعلق ایک
دوسری حدیث میں غریبوں کی دلداری کے لئے فرمایا کہ تم لوگ اگر ایمان پر قائم رہو تو
امیروں کی نسبت پانچ سو سال پہلے جنت میں جاؤ گے اور ظاہر ہے کہ آخرت کی جاودانی زندگی
Page 151
139
کے مقابل پر دنیا کی چار روزہ زندگی کیا حقیقت رکھتی ہے ؟ اور پھر یہ کہتے ہوئے غریبوں کی
مزید تسلی فرمائی کہ الْفَقْرُ فَخری یعنی اے میری اُمت کے غریب لوگو! دیکھو میں نے اپنے
واسطے بھی دنیا کی کوئی دولت جمع نہیں کی بلکہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور تم میں سے ہی ایک
غریب انسان ہوں اور اس فقر میں ہی میر افخر ہے“..دوسری طرف اوپر کی حدیث میں ”پسینہ خشک ہونے سے پہلے “ کے الفاظ فرما کر یہ
لطیف اشارہ بھی کیا ہے کہ خدا کے نزدیک سچا مز دور وہ ہے جو اپنے کام میں پسینہ بہاتا ہے.یو نہی دکھاوے کے طور پر کام کرنے والا اور مالک کی نظر سے اوجھل ہونے پر ستی دکھانے
والا یا خیانت کرنے والا شخص ہر گز خدا کے نزدیک سچا مزدور نہیں سمجھا جا سکتا.پس ایک
طرف آقا کا فرض ہے کہ وہ اجیر کو واجبی مزدوری دے اور اسکی مزدوری میں دیر نہ کرے اور
اس کے حقوق کا خیال رکھے تو دوسری طرف مزدور کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ اپنے کام میں پسینہ
بہا کر اپنے آپ کو سچا اور دیانت دار مز دور ثابت کر دے.یہی وہ وسطی تعلیم ہے جو مالک اور
مزدور اور آقا اور اجیر کے درمیان اچھے تعلقات پیدا کر کے سوسائٹی میں حقیقی امن کی بنیاد بن
سکتی ہے.: تفسير روح البيان، سورة العنكبوت، آيت 46 تا 49 ( ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن.....)
1
Page 152
140
35
بد ترین دعوت وہ ہے
جس میں صرف امیروں کو بلایا جائے
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ هَرُ الطَّعَامِ طَعَامُ الوَلِيمَةِ.يُدعَى لَهَا الأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الفُقَرَاءُ، وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ
وَرَسُولَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
(صحيح البخارى كتاب النكاح باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله)
ترجمہ: ابوہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے
تھے کہ بد ترین دعوت وہ ہے جس میں امیر لوگ تو بلائے جائیں مگر غریبوں کو نظر انداز کر دیا
جائے اور دوسری طرف جو شخص کسی کی دعوت کو رد کرتا ہے وہ خدا اور اس کے رسول لیلی لیلی کی کو
نافرمان ہے.تشریح: اسلام نے دولت کے سمونے اور غریب و امیر کے فرق کو کم سے کم حد کے
اندر محدود کرنے کی جو کوشش کی ہے وہ ظاہر اور عیاں ہے.اس تعلق میں سب سے زیادہ
Page 153
141
باعث تکلیف اور باعث اعتراض تمدنی میل ملاپ کا فرق ہوتا ہے جو گویا امیر وں اور غریبوں کو
دو علیحدہ علیحدہ کیمپوں کی صورت دے کر انکے اندر ایک دائمی رقابت اور کش مکش کا رنگ پیدا
کر دیتا ہے.اسلام نے اس کش مکش کو دور کرنے اور جذباتی فرق کو سمونے کے لئے انتہائی
کوشش کی ہے.چنانچہ سب سے پہلے تو اسلام نے سارے مسلمانوں کو بھائی بھائی قرار دے کر
ایک لیول پر کھڑا کر دیا ہے اور پھر حقوق کے معاملہ میں سب کے واسطے ترقی کا ایک جیسا رستہ
کھول کر ملکی اور قومی عہدوں کو کسی ایک فریق کی اجارہ داری نہیں بنے دیا بلکہ حکم دیا کہ قومی
اور ملکی عہدہ داروں کا انتخاب بلالحاظ غریب و امیر ، بلالحاظ قوم و قبیلہ محض اہلیت کی بناء پر ہونا
چاہیے.اس کے علاوہ غریبوں اور امیروں میں تمدنی تعلقات کو ترقی دینے اور انہیں گویا ایک
خاندان کی صورت میں اکٹھا رکھنے کے لئے آنحضرت
صلی ا لم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی
میر شخص دعوت کرے تو اس میں لازماً غریبوں کو بھی بلائے اور جب کوئی غریب شخص دعوت
کرے تو امیر لوگ ایسی دعوت میں شرکت سے ہر گز انکار نہ کریں.چنانچہ موجودہ حدیث اسی
مشتمل ہے.اس حدیث میں آنحضرت صلی کم فرماتے ہیں اور کن زور دار الفاظ میں
فرماتے ہیں کہ ”بد ترین دعوت وہ ہے جس میں امیر لوگوں کو تو بلایا جائے مگر غریبوں کو نظر
انداز کر دیا جائے “ اور پھر دوسری طرف امیروں کو متنبہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی غریب شخص
تمہاری دعوت کرے تو تمہارے لئے ہر گز جائز نہیں کہ اس کی غربت کا خیال کر کے اس کی
ارشاد پر
Page 154
142
دعوت کور د کر دو اور جو شخص ایسا کرے گا ” وہ خدا اور اس کے رسول کا نافرمان ہے “اور ایک
دوسری حدیث میں فرماتے ہیں کہ
لَوْ دُعِيْتُ إِلَى كُرَاعٍ لَأَجَبْتُ
یعنی اگر کوئی غریب شخص بکری کا ایک کھر یا پایہ پکا کر بھی مجھے اپنے گھر پر بلائے تو
میں اس کی دعوت کو ضرور قبول کروں گا.“
اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے
نادانستہ طو پر بلال اور بعض دوسرے غریب مسلمانوں کی کچھ دل شکنی ہو گئی.جب آنحضرت
صلی للی کم کو اس کا علم ہوا تو آپ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا.”ابو بکر جن غریبوں کا
دل دکھا ہے ان کی دلداری کرو کیونکہ ان کی دلداری میں خدا کی خوشنودی ہے.“ حضرت
ابو بکر فوراً ان لوگوں کے پاس گئے اور عاجزی سے عرض کیا.”بھائیو! مجھے خدا کے لئے معاف
کرنا.میری نیت دل شکنی کی نہیں تھی 2.کیا اس تعلیم کے ہوتے ہوئے ایک سچی اسلامی
سوسائٹی میں کوئی ناگوار طبقے پیدا ہو سکتے ہیں ؟ ہر گز نہیں، ہر گز نہیں بلکہ قصور ہمارا ہے جنہوں
نے اسلام کی تعلیم کو بھلا کر سوسائٹی میں رقیبانہ کیمپ قائم کر رکھے ہیں.بخاری کتاب النکاح باب من اجاب الى كراع
2 : مسلم کتاب فضائل الصحابہ باب من فضائل سلمان
Page 155
143
36
اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے
عنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أَن رَسُولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَهُوَ عَلى المنير.وَهُوَ يَذْكُرُ الصَّدَقَةَ، وَالتَّعَقُفَ عَنِ الْمَسْأَلَةِ : اليَدُ العُلْيَا خَيْرُ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَ.(موطا امام مالك كتاب الصدقة باب ما جاء من التعفف عن المسألة)
ترجمہ : عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی الیم
نے منبر پر چڑھ کر خطبہ دیا اور اس میں ایک طرف صدقہ و خیرات کی اور دوسری طرف سوال
سے بچنے کی نصیحت فرمائی اور فرمایا.اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے.“
تشریح: غربت اور فقر کے تمام امکانی خطرات میں سب سے زیادہ سنگین پہلو دنائت
اور پست خیالی اور دوسروں کے سہارے پر زندگی گزارنے کی عادت ہے جو اکثر غریبوں میں
پیدا ہو جاتی ہے.جب ایک غریب انسان امیروں کی فارغ البالی کی طرف دیکھتا ہے تو ایک
طرف اس کے اندر پست خیالی اور احساس کمتری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور دوسری طرف وہ اپنی
حالت کو بہتر بنانے کے لئے متمول لوگوں سے سوال کرنے کا عادی ہو جاتا ہے.ہمارے آقا
آنحضرت علی ایم کی دور بین نظر نے غریب کے اس امکانی خطرہ کو دیکھا اور آپ کی روح اس
Page 156
144
خطرہ کے سد باب کے لئے بے چین ہو گئی.چنانچہ آپ کے احکام اس قسم کے ارشادات سے
بھرے پڑے ہیں جن میں سوال کرنے کو انتہائی کراہت کی نظر سے دیکھا گیا ہے اور غریبوں
کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ محنت کی روزی کمائیں اور سوال کرنے سے پر ہیز کریں.زیر نظر
حدیث بھی ان حدیثوں میں سے ایک ہے.اس حدیث میں آنحضرت صلی الی یکم فرماتے ہیں کہ گو
متمول لوگوں کا فرض ہے کہ وہ اپنے غریب بھائیوں کی امداد کریں مگر غریبوں کو بہر حال
سوال سے پر ہیز کرتے ہوئے اپنے آپ کو باوقار رکھنا چاہیے اور پھر غربا میں عزت'
زت نفس کا
جذبہ پیدا کرنے کے لئے فرماتے ہیں کہ اوپر کا ہاتھ (یعنی دینے والا ہاتھ ) نیچے کے ہاتھ (یعنی
لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے.“ ان مختصر الفاظ میں آپ نے خود داری اور عزت نفس کی
وہ روح بھر دی ہے جس کی کامل تفصیل شاید ضخیم کتابوں میں بھی نہ سما سکتی.صحابہ کی مقدس جماعت نے جب آپ کے اس ارشاد کو سناتو اسے اپنے سر آنکھوں
پر جگہ دی.چنانچہ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ کے اس ارشاد کے بعد میں نے
کبھی کسی سے کوئی امداد نہیں لی.مجھے خلفاء کی طرف سے مقررہ امداد کی رقم آتی تھی مگر میں یہ
کہتے ہوئے ہمیشہ انکار کر دیتا تھا کہ رسول اللہ صلی علیم نے جس ہاتھ کو اونچارکھنے کا حکم دیا ہے میں
اسے نیچا نہیں ہونے دوں گا.حضرت علی آنحضرت صلی الی یکم کے چچازاد بھائی بھی تھے اور داماد
بھی تھے اور پھر آپ کے بعد اسلام کے چوتھے خلیفہ بھی ہوئے اور قریش کے ایک نہایت
معزز گھرانے سے تعلق رکھتے تھے ان کا ہجرت کے بعد یہ حال تھا کہ کلہاڑا لے کر جنگل میں
1 : بخاری کتاب الزكاة باب الاستعفاف عن المسئلة
Page 157
145
جاتے اور لکڑی کاٹ کر مدینہ میں لاتے اور اسے بازار میں بیچ کر اپنا گزارہ چلاتے تھے مگر کبھی
کسی کے سامنے دست سوال دراز نہیں کیا.ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں.انہیں بعض اوقات کئی کئی دن کا فاقہ ہو جاتا
تھا مگر کبھی کسی سے سوال نہیں کیا.ایک دفعہ بھوک نے نڈھال کر دیا تو صرف حضرت ابو بکر
اور حضرت عمرؓ سے اتنا پوچھا کہ فلاں قرآنی آیت کے کیا معنی ہیں ؟ اس آیت میں بھوکوں کو
کھانا کھلانے کی تاکید تھی مگر اس وقت حضرت ابو بکر اور حضرت عمرؓ نے ان کا یہ اشارہ نہیں
سمجھا اور معمولی تشریح بیان کر کے آگے روانہ ہو گئے.اتفاق سے آنحضرت صلی اللہ کی یہ گفتگو
سن رہے تھے.آپ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو آواز دی کہ معلوم ہوتا ہے تمہیں بھوک لگی
ہے.آؤ ادھر آؤ.پھر آپ نے انہیں کچھ دودھ پینے کو دیا.اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ ایک
دفعہ ایک سفر پر جاتے ہوئے ایک گھوڑے سوار معزز صحابی کا کوڑا ان کے ہاتھ سے نیچے گر گیا.اس وقت ان کے آس پاس بعض پیدل لوگ بھی سفر کر رہے تھے مگر انہوں نے خود سواری
سے نیچے اتر کر اپنا کوڑا اٹھایا اور کسی سے امداد کے طالب نہیں ہوئے اور جب ان کے ایک
ساتھی نے ان سے کہا کہ آپ نے ہمیں کیوں نہ کہہ دیا کہ ہم آپ کا کوڑا اٹھا کر آپ کو دے
دیتے تو انہوں نے جواب میں کہا کہ رسول خدا نے سوال سے منع کیا ہے اور میں اگر آپ سے
کوڑا اٹھانے کو کہتا تو یہ بھی گویا سوال ہی کا رنگ ہو جاتا.: بخاری کتاب الرقاق باب كيف كان عيش رسول اللہ صلعلم
2 : ابن ماجہ کتاب الزکاۃ باب کراھیۃ المسئلة
Page 158
146
الغرض آنحضرت
صلی نام کے صحابہ نے تعفف اور قناعت اور خود داری کا وہ نمونہ
دکھایا کہ تاریخ اس کی نظیر لانے سے عاجز ہے اور آنحضرت صلی للی کم کی تعلیم کا کمال یہ ہے کہ
ایک طرف اغنیاء کو ہدایت دی کہ اگر کوئی سوال کرے تو اسے رد نہ کرو اور دوسری طرف
غرباء کو یہ تاکید فرمائی کہ عزت کی روٹی کھاؤ اور سوال سے پر ہیز کرو.بظاہر یہ دونوں متضاد
باتیں نظر آتی ہیں لیکن حق یہ ہے کہ ان دونوں باتوں کا مرکب نظر یہ ہی امیر و غریب کے
باو قار برادرانہ تعلق کی صحیح بنیاد بن سکتا ہے.
Page 159
147
37
اپنے وارثوں کو اپنے پیچھے اچھی حالت میں چھوڑو
عَن سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَعُودُني وأنا يمكةَ..قَالَ..إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ
تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمُ
(صحيح البخاری کتاب الوصايا باب ان يترك ورثته اغنياء خير من ان يتكففوا الناس)
ترجمہ: سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں مکہ میں بیمار ہوا
اور رسول اللہ میری عیادت کے لئے تشریف لائے تو مجھ سے فرمایا کہ اگر تم اپنے پیچھے اپنے
وارثوں کو غنی چھوڑ کر جاؤ تو یہ اس سے بہتر ہے کہ تم انہیں ایسی حالت میں چھوڑو کہ وہ
دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں.تشریح: یہ الفاظ آنحضرت صلی علیم نے اس وقت فرمائے تھے جب کہ آپ کے
مقرب صحابی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ مکہ کے سفر کے دوران بیمار پڑ گئے اور انہوں نے
یہ خیال کر کے کہ شاید میری وفات قریب ہے.آنحضرت صلی الہ ظلم کے سامنے خواہش ظاہر کی
Page 160
148
کہ میں اپنے پیچھے اپنا سارا مال خدا کے رستے میں وقف کرنا چاہتا ہوں.آپ نے فرمایا.نہیں یہ
زیادہ ہے میں اس کی اجازت نہیں دیتا.اس پر انہوں نے دو تہائی مال وقف کرنا چاہا مگر آپ نے
اس کی بھی اجازت نہیں دی.آخر حضرت سعد نے ایک تہائی کی اجازت مانگی.آپ نے اس کی
اجازت دی مگر ساتھ ہی فرمایا کہ اگر تم اپنے پیچھے اپنے وارثوں کو غنی چھوڑ کر جاؤ تو یہ اس سے
بہتر ہے کہ تم انہیں ایسی حالت میں چھوڑو کہ وہ دوسروں کے سامنے دست سوال دراز کرتے
پھریں.اس حکیمانہ ارشاد سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام پیش آمدہ حالات کے ماتحت ظاہری
اسباب کو بھی مد نظر رکھتا اور دور اندیشی کی تعلیم دیتا ہے اور اس بات کو ہر گز پسند نہیں کرتا کہ
ایک ایسا مسلمان جو مال رکھتا ہے وہ اپنے وارثوں کو محروم کر کے سارا مال خدا کے رستہ میں دے
جائے اور اس کی پیچھے اس کے وارث بھیک مانگتے پھریں.مگر افسوس ہے کہ آج کل بہت سے مسلمانوں نے تو کل کا غلط مطلب سمجھ رکھا ہے
اور یہ خیال کر رکھا ہے کہ جس بات کو خدا پر چھوڑا جائے اس میں ظاہری تدابیر کی طرف سے
بالکل آنکھیں بند کر لینی چاہیں حالانکہ اسلامی تو کل کا ہر گز یہ مطلب نہیں بلکہ صحیح اسلامی
تو کل یہ ہے کہ اپنے حالات اور اپنی طاقت کے مطابق ساری ضروری تدبیریں اختیار کی جائیں
اور اس کے ساتھ خدا پر تو کل بھی کیا جائے اور یقین رکھا جائے کہ ان ظاہری تدبیروں کے
باوجود فتح و ظفر کی اصل کنجی صرف خدا کے ہاتھ میں ہے.یہ ایک بہت مشکل بلکہ بظاہر متضاد
مقام نظر آتا ہے جس پر عمل کرناتو در کنار اس کا سمجھنا بھی آسان نہیں مگر حق یہی ہے کہ صحیح
اسلامی تو کل یہ ہے کہ ایک طرف تمام ضروری تدبیریں اختیار کی جائیں اور دوسری طرف ان
Page 161
149
تدبیروں کی تاروں کے متعلق یقین رکھا جائے کہ وہ خدا کے ہاتھ میں ہیں اور یہ کہ بہر حال
ہو گا وہی جو خدا کی مشیت ہے اور اگر غور کیا جائے تو یہ دونوں چیزیں متضاد نہیں ہیں کیونکہ
جب ہر تقدیر خیر و شر اور تمام خواص الاشیاء اور ہر قسم کے اسباب اور مسببات کا خالق و مالک خدا
ہی ہے تو اس میں کیا شک ہے کہ ظاہری تدبیروں کے باوجود ہمارے اعمال کے نتائج کی آخری
تاریں خدا کے ہاتھ میں سمجھی جائیں گی.چنانچہ روایت آتی ہے کہ ایک دفعہ ایک بدوی رئیس
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور ملاقات کے شوق میں اپنی اونٹنی مسجد
نبوی کے دروازہ کے باہر کھلی چھوڑ آیا.جب وہ آپ سے مل کر واپس گیا تو اس کی اونٹنی بھاگ
کر غائب ہو چکی تھی.وہ گھبرایا ہوا مسجد میں واپس آیا اور آنحضرت صلی کریم سے عرض کیا کہ یا
رسول اللہ ! میں نے خدا کے تو کل پر اپنی اونٹنی کو چھوڑا تھا مگر جب آپ سے مل کر باہر گیا ہوں
تو وہ بھاگ چکی تھی.آپ نے فرمایا.اِعْقَلُهَا وَتومحل : " یعنی ایک طرف اپنی اونٹنی کا گھٹنا
باند ھو اور دوسری طرف خدا پر توکل کرو“ اور یہی وہ لطیف الفاظ ہیں جن پر مولانا رومی علیہ
رحمتہ نے یہ مشہور مصرعہ نظم کیا ہے کہ
1
بر تو کل زانوی اشتر ببند 2
خلاصہ یہ کہ حدیث زیر نظر میں آنحضرت صلی یم نے ایک طرف اولاد کے باوقار
گزارے کے لئے والدین کو دور بینی اور دور اندیشی کی تعلیم دی ہے کہ جہاں تک تمہارے
: في ظلال القرآن ، جلد 5 ، زیر آیت الم غلبت الروم فى ادنى الارض
2 : مثنوی و مولوی و معنوی (مولانا رومی) باب ” باز ترجیح نهادن شیر جهد را بر تو کل و تسلیم “جلد 1 صفحہ 132
Page 162
150
اختیار میں ہے اپنے متعلقین کو بے سہارا نہ چھوڑو اور ان کے لئے باوقار زندگی کا انتظام کرو اور
دوسری طرف آپ نے ضمناً اس حدیث میں یہ اشارہ بھی فرمایا ہے کہ ظاہری تدبیریں توکل
کے خلاف نہیں.پس پہلے اپنی طاقت اور ذرائع کے مطابق ظاہری تدبیریں اختیار کرو اور پھر
خدا پر توکل کرو.بے شک جیسا کہ میں نے اوپر لکھا ہے یہ ایک نہایت مشکل مقام ہے کیونکہ
انسان اپنی کمزوری میں ایک طرف جھک جانے کا عادی ہوتا ہے وہ یا تو صرف ظاہری تدبیروں
پر جھک کر انہی کو اپنا خدا فرض کر لیتا ہے اور یا ظاہری تدبیروں کو کلیتاً چھوڑ کر خدا سے یہ امید
لگا بیٹھتا ہے کہ میں خدا کے بنائے ہوئے اسباب کو ٹھکراتا ہی رہوں.وہ بہر حال اپنے عرش سے
اتر کر خود میرے کاموں کو سر انجام دے گا مگر حق یہی ہے کہ یہ دونوں نظریے باطل اور
خلاف تعلیم اسلام ہیں اور سچا فلسفہ یہی ہے جس پر نیک لوگوں کا ہر زمانہ میں عمل رہا ہے کہ
” ایک طرف اپنی اونٹنی کا گھٹنا باند ھو اور دوسری طرف خدا پر توکل کرو.“
Page 163
151
38
ہر شخص اپنی جگہ حاکم ہے اور اپنی حکومت کے
دائرہ میں جواب دہ ہو گا
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّكُمْ
رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
(بخاری کتاب النکاح باب المرأة راعية فى بيت زوجها)
ترجمہ : عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی ایام کو یہ
فرماتے ہوئے سنا کہ تم میں سے ہر شخص اپنے دائرہ کے اندر ایک حاکم کی حیثیت رکھتا ہے اور تم
میں سے ہر ایک کو اپنے ماتحتوں کے متعلق پوچھا جائے گا.تشریح: ہر انسان کے ساتھ کچھ حقوق لگے ہوئے ہیں اور کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں اور
یہ لطیف حدیث انہی دو باتوں کی طرف توجہ دلاتی ہے.آنحضرت صلی علیہ یکم فرماتے کہ ہیں کہ ہر
انسان کسی نہ کسی جہت سے حاکم ہوتا ہے خواہ وہ دوسری حیثیت سے کتناہی محکوم ہو.ایک شخص
جو کسی صیغہ میں ملازم ہے وہ اپنے صیغہ میں اپنے افسر کے ماتحت ہو گا لیکن گھر میں وہ اپنے بیوی
Page 164
152
بچوں کا حاکم بھی ہو گا.ایک عورت اپنے خاوند کے ساتھ محبت کے اعلیٰ مقام پر ہونے کے
باوجود انتظامی رنگ میں محکوم ہوتی ہے مگر گھر کے بچوں اور نوکروں پر اور نیز خاوند کے اس مال
پر جو عورت کے سپر د ہوتا ہے وہ حاکم بھی ہوتی ہے.اسی طرح ایک بادشاہ سے لے کر غلام
تک اور ایک جرنیل سے لے کر سپاہی تک اور ایک گورنر سے لے کر دفتر کے چپڑاسی تک سب
اپنے اپنے دائرہ کے اندر حاکم بھی ہیں اور محکوم بھی.بادشاہ ساری رعایا کا حاکم ہوتا ہے مگر وہ
خدا کا یا دوسرے لفظوں میں قضا و قدر کے قانون کا محکوم بھی ہوتا ہے اور یہی حال تمام
دوسرے افسروں اور ماتحتوں کا ہے کہ وہ ایک جہت سے حاکم ہیں اور دوسری جہت سے محکوم
ہیں اور آنحضرت صلی اللہ ظلم کے ارشاد کے مطابق یہ سب لوگ اپنے اپنے دائرہ میں اپنی اپنی رعایا
کے متعلق پوچھے جائیں گے کہ انہوں نے اپنے ماتحتوں کا حق ادا کیا یا نہیں ؟ حتی کہ جب ہم اس
آخری انسان پر پہنچ جاتے ہیں جس کے نیچے بظاہر کوئی محکوم نظر نہیں آتا تو غور کرنے سے یہ
پتہ لگتا ہے کہ دراصل وہ بھی ایک چیز کا حاکم ہے اور یہ چیز اس کا نفس ہے جس پر اسے کامل
اختیار دیا گیا ہے.پس اس سے اس کے نفس کے متعلق سوال کیا جائے گا کہ اس نے کہاں تک
اس کا حق ادا کیا ہے.اس طرح آنحضرت ملا لی ایم نے ہر شخص کو ہوشیار کیا ہے کہ خواہ وہ
سوسائٹی کے کسی طبقہ سے تعلق رکھتا ہے بہر حال وہ کسی نہ کسی حیثیت میں حاکم ہے اور اسے
اپنے دائرہ حکومت میں اپنے کاموں کی جواب دہی کے لئے تیار رہنا چاہیے.دوسری طرف یہ حدیث لوگوں کے لئے ایک بشارت بھی ہے اور ان کی ہمتوں کو بلند
کرتی ہے کہ خواہ اس وقت تم درجہ میں کتنے ہی نیچے ہو تم بہر حال دوسری جہت سے حاکم بھی ہو.
Page 165
153
پس تمہیں خدا کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے تمہیں اپنی ازلی حکومت کا ایک منصب عطا کر
رکھا ہے اور اگر تم اس کے شکر گزار ہو گے تو کل کو تم ترقی کر کے اپنی موجودہ حکومت سے بہتر
حکومت کے وارث بن سکتے ہو.الغرض حقوق اور ذمہ داریوں کا یہ لطیف مرکب انسان کے لئے
ایک بشارت بھی ہے اور انذار بھی.بشارت اس لئے کہ ہر حکومت خدا کا ایک انعام ہے اور انذار
اس لئے کہ ہر حکومت کے ساتھ کچھ ذمہ داریاں بھی وابستہ ہوتی ہیں.پس سچا مومن وہ ہے جو
بشارت کے پہلو پر شکر گزار ہو تا اور ذمہ داری کے پہلو کی طرف سے ہمیشہ چوکس و ہوشیار رہتا ہے
کہ اسی میں اس کی ترقی کا ازلی راز ہے.
Page 166
154
39
علم سیکھنا
ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے
عنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : طَلَبُ
العِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ.(سنن ابن ماجه کتاب السنة باب فضل العلماء والحث على طلب العلم)
ترجمہ: انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی ا یکم فرماتے تھے
کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور مسلمان عورت پر فرض ہے.تشریح: چونکہ اسلام کی بنیاد اس یقینی علم پر ہے جو خدا کی طرف سے آخری شریعت کی
صورت میں نازل ہوا ہے اور پھر اسلام ہر بات کو دلیل کے ذریعہ منواتا ہے.اس لئے اسلام میں
علم کے حصول کے لئے انتہائی تاکید کی گئی ہے اور یہ حدیث ان بہت سی حدیثوں میں سے ایک ہے
جن میں آنحضرت صلی اللہ ﷺ نے مردوں اور عورتوں کو علم سیکھنے کی تاکید فرمائی ہے اور اس ہدایت پر
آپ کو اتنا اصرار تھا کہ ایک دوسری حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ علم سیکھو خواہ اس کے لئے
Page 167
155
تمہیں چین کے کناروں تک جانا پڑے اور یاد رہے کہ اس زمانہ کے حالات کے لحاظ سے چین کا
ملک نہ صرف عرب سے ایک دور ترین ملک تھا بلکہ اس کے رستے بھی ایسے مخدوش تھے کہ وہاں
تک پہنچنا غیر معمولی اخراجات اور غیر معمولی کوفت اور غیر معمولی خطرے کا موجب تھا.اس لئے
آنحضرت صلی اللہ و ہم نے چین کے ملک کو مثال کے طور پر بیان فرما کر دراصل اشارہ یہ کیا ہے کہ خواہ
تمہیں علم حاصل کرنے کے لئے کتنی ہی دور جانا پڑے اور کیسی ہی تکلیف کا سامنا ہو علم وہ چیز ہے
کہ اس کے لئے مومن کو ہر تکلیف اٹھا کر اس کے حصول کا دروازہ کھولنا چاہیے.چنانچہ تاریخ سے
ثابت ہے کہ بعض اوقات ابتدائی مسلمان آنحضرت صلی الی کمی کی ایک ایک حدیث سننے کے لئے
سینکڑوں میل دور کا سفر اور غیر معمولی اخراجات برداشت کر کے صحابہ کی تلاش میں پہنچتے تھے.چنانچہ جب ایک شخص مدینہ سے سینکڑوں میل کا سفر اختیار کر کے آنحضرت صلی الم کے صحابی
ابو درداء کے پاس ایک حدیث سننے کی غرض سے دمشق آیا تو ابو در داء نے اسے وہ حدیث بھی سنائی
اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی الہی ظلم سے سنا ہے کہ جو شخص علم حاصل کرنے کی
غرض سے کسی رستہ کا سفر اختیار کرتا ہے تو خدا تعالیٰ اس کے لئے اس علم کے علاوہ جنت کا رستہ بھی
کھول دیتا ہے اور ایک دوسری حدیث میں آنحضرت صلی یی کم فرماتے ہیں کہ ایک انسان کا درجہ
ایک ایسے عابد انسان کے مقابلہ پر جو اپنی عبادت کے باوجود علم سے خالی ہے ایسا ہے کہ جیسے عام
1 : شعب الايمان، باب السابع عشر من شعب الايمان وهو باب فى طلب العلم
2 : ابو داؤد کتاب العلم باب الحث على طلب العلم
Page 168
156
ستاروں کے مقابلہ پر چودھویں رات کا چاند ہوتا ہے اور ایک تیسری حدیث میں فرماتے ہیں کہ
ایک عالم انسان شیطان پر ہزار عابدوں سے بھی زیادہ بھاری ہوتا ہے اور ایک چوتھی حدیث میں
فرماتے ہیں کہ میری امت کی بہترین بھلائی نیک علماء میں ہے اور ایک پانچویں حدیث میں فرماتے
ہیں کہ علماء گویا نبیوں کے وارث ہوتے ہیں مگر جیسا کہ چوتھی حدیث میں اشارہ کیا گیا.وہی ہے جس کے ساتھ نیکی اور تقویٰ شامل ہو.الغرض اسلام میں علم کے حصول کی انتہائی تاکید کی گئی ہے اور سچے علم کا وہ مقام
تسلیم کیا گیا ہے جو ایمان کے بعد کسی دوسری چیز کو حاصل نہیں اور پھر علم کو ایک غیر محدود چیز
قرار دے کر ہدایت کی گئی ہے کہ خواہ تمہیں کتنا ہی علم حاصل ہو جائے پھر بھی مزید علم کے
حصول کی کوشش کرتے رہو.چنانچہ اور تو اور خود فخر موجودات سرور کائنات سید الرسل
حضرت خاتم النبیین صلی یہ تم کو خدا تعالیٰ قرآن شریف میں یہ دعا سکھاتا ہے کہ
عطا کر.قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًاء
یعنی اے رسول ! تم ہمیشہ یہ دعا مانگتے رہو کہ خدایا ! میرے علم میں بیش از بیش ترقی
: ابو داؤد کتاب العلم باب الحث على طلب العلم
2 : ابن ماجہ ، افتتاح الكتاب ، باب فضل العلماء و الحث على طلب العلم
4
3 : تفسير الكشاف ، سورة الصف آیت نمبر 6 ( و اذ قال عیسی ابن مریم یبنی اسرائیل...)
: ابو داؤد کتاب العلم باب الحث على طلب العلم
115 ::
5
Page 169
157
اور پھر جیسا کہ حدیث زیر نظر میں صراحت کی گئی ہے آنحضرت صلی یم نے علم کے
حصول کو صرف مردوں تک محدود نہیں کیا بلکہ عورتوں کو بھی اسی طرح تاکید فرمائی ہے مگر
افسوس ہے کہ ان تاکیدوں کے باوجود آج کل مسلمان مردوں اور عورتوں کا علمی معیار دوسری
قوموں کے مقابلہ پر اعلیٰ ہو نا تو در کنار کافی ادنی اور پست ہے.چنانچہ تقسیم ملکی سے پہلے ہندوستان
کی ساری قوموں یعنی ہندوؤں ، سکھوں ، غیر ملکی عیسائیوں اور پارسیوں وغیرہ کے مقابلہ پر
مسلمانوں کی خواندگی کی شرح فیصد سب سے کم تھی.دنیا کے عالم ترین مصلح کی امت کا یہ نمونہ
یقینا بے حد قابل افسوس ہے اور وقت ہے کہ مسلمان اپنے فرض کو پہچان کر دین و دنیا کے علم میں
نہ صرف اوّل نمبر حاصل کرنے کی کوشش کریں بلکہ اس مقام کو پہنچیں جس کی گرد کو بھی کوئی
دوسری قوم نہ پاسکے.
Page 170
158
40
ہر حکمت کی بات
مومن کی اپنی ہی کھوئی ہوئی چیز ہے
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الكَلِمَةُ الحِكْمَةُ
ضَالَةُ المُؤْمِنِ فَحَيْثُ وَجَدَهَا فَهُوَ أَحَقُ بِهَا.(سنن الترمذی ابواب العلم باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة)
ترجمہ : ابوہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی ا یکم فرمایا کرتے تھے
کہ حکمت اور دانائی کی بات تو مومن کی اپنی ہی کھوئی ہوئی چیز ہوتی ہے اسے چاہیے کہ جہاں بھی
اسے پائے لے لے کیونکہ وہی اس کا بہتر حق دار ہے.تشریح: یہ لطیف حدیث جو میرے اس انتخاب کی آخری حدیث ہے علم کے حصول
کا ایک بہترین ذریعہ بتاتی ہے.علم ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ صرف درس گاہوں میں شامل ہو کر یا
مسجد کے خطبات سن کر یا عالموں کی مجلس میں بیٹھ کر یا اخبار پڑھ کر یا کتابوں کا مطالعہ کر کے ہی
حاصل ہو سکے بلکہ وہ ایک بہت وسیع چیز ہے جسے آنکھیں اور کان کھول کر زندگی گزار نے والا
انسان صحیفہ عالم کی ہر سختی سے حاصل کر سکتا ہے.علم کا شوق رکھنے والے انسان کے لئے زمین
Page 171
159
و آسمان اور سورج و چاند اور ستارے اور سیارے اور جنگل و پہاڑ اور دریا و سمندر اور شہر و
ویرانے اور دیوانے و فرزانے اور انسان و حیوان اور مرد و عورت اور بچے و بوڑھے اور جاہل و
عالم اور دوست اور دشمن سب ایک کھلی ہوئی علمی کتاب ہیں جن سے وہ اپنی استعداد اور اپنی
کوشش کے مطابق علم کے خزانے بھر سکتا ہے.اس لئے ہمارے آقا ( فداہ نفسی مال لیلی
فرماتے ہیں کہ علم و حکمت کی بات مومن کی اپنی ہی کھوئی ہوئی چیز ہے.اسے چاہیے کہ جہاں
بھی اسے پائے لے لے اور اپنے دل و دماغ کی کھڑکیوں کو اس طرح کھول کر رکھے کہ کوئی علمی
بات جو اس کے سامنے آتی ہے اس کے دل و دماغ کے خزانہ میں داخل ہونے سے باہر نہ رہے.یہ وہ علم کی وسعت ہے جس کی طرف یہ حدیث اشارہ کر رہی ہے اور حق یہ ہے کہ اگر انسان
کے دل و دماغ کی کھڑکیاں کھلی ہوں تو بسا اوقات ایک عالم انسان ایک بچہ سے بھی علم حاصل
کر سکتا ہے.چنانچہ روایت آتی ہے کہ ایک دفعہ امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے ایک بچے کو
بارش اور کیچڑ میں بھاگتے ہوئے دیکھا اور اسے آواز دی کہ میاں بچے ! ذرا سنبھل کر چلو تا ایسانہ
ہو کہ گر جاؤ.بچے نے گھوم کر جواب دیا.امام صاحب آپ اپنی فکر کریں کیونکہ میں تو ایک
معمولی بچہ ہوں اگر میں گرا تو میرے گرنے کا اثر صرف میری ذات تک محدود رہے گا لیکن
آپ دین کے امام ہیں اگر آپ پھسلے تو قوم کی خیر نہیں'.امام صاحب کی طبیعت بڑی نکتہ شناس
تھی فور فر مایا کہ اس بچہ نے آج مجھے بڑا قیمتی سبق دیا ہے.1 : الدر المختار شرح تنویر الابصار صفحہ 15
Page 172
160
اس حدیث کے تعلق میں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ یہ جو اس حدیث میں
ضالة (کھوئی ہوئی چیز) کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اس میں یہ لطیف اشارہ ہے کہ ایک مسلمان کو
جو بھی حکمت اور دانائی کی بات نظر آتی ہے وہ خواہ اسے پہلے سے معلوم ہو یا نہ ہو در حقیقت
اس کا بیج اسلام میں موجود ہوتا ہے اور اسی لئے اسے صالہ کہا گیا ہے تا کہ اس بات کی طرف
اشارہ کیا جائے کہ یہ چیز حقیقتاً مومن کی اپنی تھی مگر اس کی نظر سے اوجھل رہ کر اس کے قبضہ
سے باہر رہی.اس صورت میں مومن کا یہ حق ہے کہ اسے جب بھی ایسی چیز ملے وہ اسے فوراً
لے لے.اس لئے نہیں کہ اسے کسی دوسرے کی چیز کے اڑا لینے کا موقع میسر آگیا ہے بلکہ اس
لئے کہ اسے اپنی کھوئی ہوئی چیز واپس مل گئی ہے.اسی لئے آنحضرت صلی اللہ ہم نے ضالہ کے بعد
یہ الفاظ فرمائے ہیں کہ فَهُوَ اَحَقُ بها ” یعنی مومن ہی اس چیز کا زیادہ حق دار ہے.خواہ وہ
بظاہر دوسرے کے قبضہ میں ہو اور اگر غور کیا جائے تو حقیقتاً ہر علم و حکمت کی چیز کا اصل
الاصول اسلام میں موجود ہے جیسا کہ خود قرآن شریف فرماتا ہے کہ
فِيهَا كُتُبْ قَيْمَةٌ
یعنی ہر دائمی صداقت جو انسان کے کام کی ہے وہ قرآن میں موجود ہے.“
مگر افسوس ہے کہ بہت تھوڑے لوگ ایسے ہیں جو غور کرتے اور فائدہ اٹھاتے ہیں.حق یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ ہم نے بھی جو کچھ حدیث میں فرمایا ہے وہ بھی دراصل
قرآن ہی کی تفسیر ہے لیکن ظاہر ہے کہ آپ کی نظر جہاں پہنچی ہے وہاں کسی اور کی نہیں پہنچی
1 : البينة: 4
Page 173
161
اور نہ پہنچ سکتی ہے.آپ نے خدائی تائید و نصرت سے قرآن کے مستور اشاروں کو حدیث کے
منشور اوراق پر سجا کر رکھ دیا ہے لیکن اس مادی عالم کی طرح جو حضرت آدم سے لے کر اس
وقت تک ہر زمانہ کی ضرورتوں کو پورا کرتا آیا ہے.قرآن بھی در حقیقت ایک روحانی عالم ہے
جس کے خزانے کبھی ختم نہیں ہو سکتے اور اسی لئے اس کے متعلق خد اتعالیٰ فرماتا ہے کہ
إن من قبي الا عند كا عرائدُهُ وَمَا للإلهُ إِلَّا بِقَدَرٍ تَعْلُومٍ
یعنی ہمارے پاس ( قرآن میں ) ہر قسم کے روحانی اور علمی خزانے موجود ہیں مگر ہم
انہیں ایک فیصلہ شدہ اندازے کے مطابق صرف حسب ضرورت ظاہر کرتے ہیں.“
پس اس میں کیا شک ہے کہ دراصل ہر علم و حکمت کی چیز مومن کی ضالہ ہے کیونکہ
اس کا بیچ قرآن مجید میں موجود ہے اور قرآن مومن کا اپنا خزانہ ہے خواہ کوئی شخص اس کے
اندر کے ذخیروں پر آگاہ ہو یا نہ ہو.کاش دنیا قرآن کے مقام کو سمجھے اور کاش دنیا حدیث کے
ان جواہر پاروں کی قدر بھی پہچانے جو ہمارے آقا نے قرآن کی کان سے نکال کر ہمارے
سامنے پیش کئے ہیں.وَاخِرُ دَعُونَا آنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ
1 : الحجر: 22
Page 174
162
خاتمہ اور دعا
دنیا سے میرا یہ خطاب ختم ہو الیکن انسان صرف ایک جسم تیار کر سکتا ہے.اس جسم
کے اندر روح ڈالنا خدا کا کام ہے.پس دنیا کے خطاب کے بعد میں اپنے آسمانی آقا سے جو ساری
خوبیوں کا جامع اور ساری طاقتوں کا مالک ہے عرض کرتا ہوں کہ اے میرے آقا ! میں نے اپنی
طرف سے خلوص دل اور پاک نیت کے ساتھ تیرے مقدس رسول (فداہ نفسی) کی یہ چالیس
حدیثیں مختلف کتابوں سے جمع کر کے مرتب کی ہیں مگر تیری نصرت اور تیری رحمت کے بغیر
میرا یہ کام اس برکت کو حاصل نہیں کر سکتا جو تیری طرف سے آسمان کی بلندیوں سے نازل
ہوتی اور مردہ جسموں میں جان ڈالتی اور خاک کے ذروں کو چمکتے ہوئے ستارے بنا دیتی ہے.پس اے میرے آقا! تو اب اپنے فضل و کرم سے ایسا کر کہ میری یہ مختصر سی تصنیف تیری از لی
اور ابدی برکتوں سے حصہ پائے اور تیرے مقدس رسول کا یہ کلام پاک اس رسالہ کے پڑھنے
والوں کے دلوں میں نور اور دماغوں میں روشنی اور جوارح میں برکت پیدا کرنے کا موجب ہو.اس کے ذریعہ افراد اور خاندان اپنی اصلاح کا رستہ پائیں اور قومیں اور ملتیں عروج اور ترقی کی
طرف قدم بڑھانے میں مدد حاصل کریں کیونکہ گو بظاہر یہ الفاظ سادہ ہیں لیکن اگر غور کیا
جائے تو ان کے اندر اصلاح اور ترقی کے بے شمار رستے مخفی ہیں اور اے میرے خالق و مالک
خدا! تو مجھے بھی اپنے فضل و رحمت کے سایہ میں جگہ دے اور اپنے حبیب پاک کی اس محبت
Page 175
163
کے طفیل جو تو نے میرے ناچیز دل میں ودیعت کی ہے مجھے اس دنیا میں اس کی لائی ہوئی تعلیم پر
قائم رکھ اور آخرت میں اس کے قدموں کی ٹھنڈک عطا فرما.امِين يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ
Page 177
سن اشاعت
2002
2003
2004
2004
2001
2002
1992
2000
165
کتابیات
مصنف
نام کتاب
الدر المختار شرح محمد بن علی بن محمد بن | دار الكتب العلميه
تنویر الابصار
على
بيروت
السنن الكبرى للبيهقى | ابوبکر احمد بن حسين دار الكتب العلميه،
بن على البيهقى
بيروت
المكتوبات الربانيه امام ربانی احمد بن دار الكتب العلميه
عبد الاحد
بيروت
امام مالك بن انس
موسسه الكتب
الثقافيه، بیروت
الموطا
الیواقیت والجواهر فى محی الدین ابن العربی دار الاحياء التراث،
بیان عقائد الاكابر
تحذير الناس
تفسير الكشاف
بيروت
محمد قاسم نانوتوی مکتبه رحیمیه
دیوبند، سهارنپور
محمود بن عمر زمخشری دار الكتب العربيه
تفسير روح البيان اسماعیل حقی
البروسوى
شاہ ولی الله
دهلوی
بيروت
مکتبه اسلامیه
کوئٹہ
مطبع حیدری
تفهيمات الهيه
جامع ترمذی
ابو عیسی محمد بن
دار المعرفه
عیسی بن الترمذی بیروت، لبنان
ربیع الابرار ونصوص محمود بن عمر زمخشری
بيروت
الاخبار
سنن ابن ماجه
ابو عبد الله محمد بن دار احياء التراث
یزید
بيروت
القزويني
نمبر شمار
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Page 178
2009
1417
هجری
2000
2008
2013
2006
2003
1985
2018
2009
2006
2006
166
سنن ابی داود
ابو داود سلیمان بن دار السلام ، الرياض
الأشعث السجستاني
سنن النسائى
ابو عبد الرحمن احمد بن مكتبه المعارف،
شعیب بن على النسائى الرياض
شعب الايمان
امام ابی بکر احمد بن دار الكتب العلميه،
حسين البيهقى
بيروت
صحيح البخاری
ابو عبد الله محمد بن دار الكتاب بي
اسماعيل البخاري
،بیروت
صحیح مسلم
فتوحات مکیه
مسلم بن الحجاج نور فاؤنڈیشن ،
القشيري النيسابورى
محی الدین ابن العربی دار الاحياء التراث،
ربوها
بيروت
في ظلال القرآن
سید قطب
دار الشروق
بيروت
كنز العمال في سنن علاؤ الدین علی المتقی موسسه الرساله
الاقوال والافعال بن حسام الدین
بيروت
الهندي
مرشد ذوى الحجا و محمد الامين بن عبد الله | دار طوق النجاة
الحاجه
(شرح سنن ابن ماجه )
بن یوسف بن حسن
بيروت
مسند احمد بن حنبل امام احمد بن حنبل مکتبه رحمانیه
لاهور
مثنوی و مولوی
مولانا جلال الدین رومی الفيصل ، لاهور
و معنوی
معجم الكبير
حافظ ابى القاسم سليمان بن احمد | الرياض
طبرانی
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
24