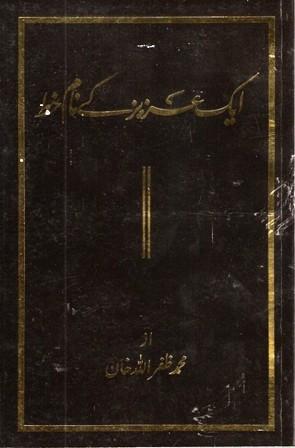Complete Text of AzizKNam
Content sourced fromAlislam.org
Page 1
ایک عزیز کے نام خط
از
محمد ظفر اللہ خان
Page 2
ایک عزیز کے نام خط
EIK AZIZ KEI NAAM KHAT
A letter to a dear one
(Urdu)
by: Chaudhary Muhammad Zafrullah Khan
First Published in India in 1940
Re-Published in different countries
Present edition published in UK in 2007
Islam International Publications Limited
Published by:
Islam International Publications Ltd."Islamabad" Sheephatch Lane
Tilford, Surrey GU10 2AQ
United Kingdom
Printed in UK at:
Raqeem Press
Tilford, Surrey
ISBN: 1 85372 942 6
Page 3
7
11 13 ±
9
11
14
فہرست مضامین
پبلشرز نوٹ بابت ایڈیشن 2007ء
اس خط سے متعلق ایک ضروری گذارش
زندگی کا نازک مرحلہ
دور سے
زندگی کا مقصد
امیر الہی
ترقی کے دور
انسانی روح کی پیدائش
زندگی کی انواع
انسان پر خدائی انعامات
زندگی کا کمال
معرفت الہی کے لئے صفات الہی کا علم ضروری ہے
ہمارا خدا
توحید باری
ربّ العالمین
رحمن
رحیم
15
16
18
19
21
23
24
25
28
2222
31
31
32
3
Page 4
مالک یوم الدین
مجیب الدعوات
قبولیت دعا
الہام الہی
خدائے غفور
تخلق با خلاق الله
پاکیزہ زندگی
خدا کا عدل ورحم
تعلق باللہ کا ذریعہ
الہام کی کیفیت
قرآنی خصوصیت
قرآن مجید میں کامل ہدایت ہے
قرآن مجید کا بڑا معجزہ
حفاظت قرآن
قرآن میں ترتیب
ایک غیر محدود خزانہ
اسوۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل اخلاق
بیوی سے سلوک
بچوں پر شفقت
غلاموں سے سلوک
43
45
40
37
38
35
36
33
22232883 & to  w w w w w 32
63
65
66
62
48
50
51
52
53
57
58
61
46
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک حاکم کی حیثیت میں
4
Page 5
69
71
72
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سادہ زندگی
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عفو اور رحم
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت
اعتدال پسندی
اسلام میں رہبانیت نہیں
حقوق العباد
حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت
حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے پہلے اسلام کی نازک حالت
حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا عشق
74
76
76
77
79
82
90
92
93
94
N0012222232
79
104
105
107
108
109
115
119
127
5
اسلام کا دوسرا دور
سائنس اور مذہب
ملائکہ کا وجود
روحانی اصلاح میں نماز کا مقام
ذکر الہی
روزه
حج
اخلاق
فلسفه اخلاق
اخلاق کے مدارج
از دواجی زندگی
تربیت اولاد
Page 6
130
131
133
134
136
139
142
6
عام
تمدنی آداب
اقتصادی نظام
سود کی ممانعت
اسلامی قانون وراثت
موت کی حقیقت
حالات بعد الموت
کتب برائے مطالعہ
Page 7
پبلشر ز نوٹ بابت ایڈیشن 2007 ء
حضرت چوہدری محمد ظفر اللہ خان صاحب رضی اللہ عنہ نے اگر چہ اپنے ایک عزیز کے نام تحریر فرمایا تھا لیکن تاہم اس میں
سبھی کیلئے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل
کرنے کیلئے ہدایت اور راہنمائی موجود ہے.بالخصوص آجکل کے زمانہ میں تربیت اور راہنمائی کیلئے
اسکی بہت ضرورت ہے.یہی وجہ ہے کہ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خليفةالمسيح الخامس
ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے اس کی از سر نو اشاعت کے لئے ہدایت فرمائی ہے.جماعتوں کو
کوشش کرنی چاہئے کہ ہر اردو سمجھنے والے گھرانے میں یہ کتاب موجود ہو اور اس کا مطالعہ کیا جائے
اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے.کتاب میں مذکورہ آیات قرآن جن کا حوالہ نہیں دیا گیا تھا، ان کا حوالہ اس ایڈیشن میں
قارئین کی سہولت کیلئے دیدیا گیا ہے.اسطرح کتاب
کو کمپیوٹر پر از سر نو ٹائپ سیٹ کروایا گیا ہے.جب کسی کتاب کو ٹائپ کیا جاتا ہے تو ٹائپنگ کی بہت سی اغلاط کا امکان ہوتا ہے اسلئے بہت احتیاط
کے ساتھ پروف ریڈنگ کی ضرورت ہوتی ہے.کوشش کی گئی ہے کہ پروف ریڈنگ میں کوئی غلطی نہ
رہ جائے لیکن اگر ایسا ہو تو ہم معذرت خواہ ہیں.اس ایڈیشن کی ٹائپ سیٹنگ محمود احمد ملک صاحب ( مرکزی شعبہ کمپیوٹر یوکے) نے کی ہے
جبکہ اصل کتاب کے ساتھ لفظاً لفظاً موازنہ اور پروف ریڈنگ میں خاکسار کی مددخاکسار کی اہلیہ
ریحانه شمس صاحبہ نے کی ہے.اللہ تعالیٰ اُن تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے اس ایڈیشن
کی طباعت کے مراحل میں کسی بھی رنگ میں خدمت کی توفیق پائی ہے.اسی طرح دعا ہے کہ
اللہ تعالیٰ اس کتاب کو ہر لحاظ سے بابرکت فرمائے اور بہتوں کی ہدایت کا موجب ہو.آمین
منیر الدین شمس
ایڈیشنل وکیل التصنیف - لندن
فروری 2007ء
7
Page 9
بسم الله الرّحمن الرّحيم
نحمده ونصلى على رسوله الكريم
اس خط سے متعلق ایک ضروری گذارش
مجھے بچپن سے تصنیف کا شوق ہے.اس لئے ہر عمدہ تصنیف جو کسی کے ہاتھ سے نکلتی
ہے وہ خاص خوشی کا باعث ہوتی ہے.مکرمی چوہدری سر محمد ظفر اللہ خان صاحب ممبر
ایگزیکٹو کونسل وائسرائے ہند نے اپنی اس قیمتی تصنیف میں جو اس وقت دوستوں کے ہاتھ
میں ہے نہ صرف جماعت احمدیہ کی بلکہ بنی نوع انسان کی ایک عمدہ خدمت سرانجام دی ہے
کیونکہ اس تصنیف میں وہ رستہ بتایا گیا ہے جس پر چل کر انسان ایک با اخلاق اور با خدا انسان
بن سکتا.ہے دنیا میں اہل دنیا کی علمی اور اقتصادی اور سیاسی خدمت کرنے والے لوگ تو بہت
ہیں مگر اخلاقی اور روحانی خدمت کی طرف موجودہ ماڈی زمانہ میں بہت کم لوگوں کو تو جہ ہے اور
اس لحاظ سے چوہدری صاحب مکرم کی یہ خدمت جس کی اس زمانہ میں دنیا کو از حد ضرورت
ہے بہت قابل قدر ہے.احمدی نوجوان تو خیر ا سے پڑھیں گے ہی مگر ضرورت اس بات کی
ہے کہ اس مفید تصنیف کو غیر احمدی اور غیر مسلم اصحاب تک بھی کثرت کے ساتھ پہنچایا جائے
تا کہ وہ بھی اس پاکیزہ چشمہ کے مصفیٰ پانی سے سیراب ہوں جو آج سے ساڑھے تیرہ سوسال
قبل عرب کی سرزمین میں پھوٹا اور پھر کچھ عرصہ کے بعد دنیا کی آلائشوں سے مکدر ہو کر اسی
طرح زمین میں گم ہو گیا جس طرح نا اہل لوگوں کے زمانہ میں قیمتی چشمے گم ہو جایا کرتے ہیں
اور پھر اس زمانہ میں یہی چشمہ قدرت کے مخفی ہاتھوں سے دوبارہ صاف ہوکر پنجاب کی
سرزمین سے پھوٹ کر بہہ نکلا.چوہدری صاحب کی یہ تصنیف ایک خط کی صورت میں ہے جو انہوں نے احمدیت کی
9
Page 10
آئندہ نسل کے متعلق اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے اپنے ایک عزیز کے نام تحریر فرمایا
ہے اور جسے اب رفاہ عام کی غرض سے شائع کیا جارہا ہے.اس تصنیف کی مندرجہ بالا نوعیت
نے اس کے اندر ایک خاص اثر پیدا کر دیا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے چوہدری صاحب کے
الفاظ اس خاص قسم کی بجلی کی رو سے معمور ہیں جو قانونِ فطرت کے ماتحت ایک محبت کرنے
والے انسان اور محبت کئے جانے والے انسان کے درمیان قدرتاً جاری رہتی ہے.مجھے اس
عزیز کا نام معلوم ہے.مگر جب چوہدری صاحب نے نام ظاہر نہیں کیا تو میں کیوں ظاہر
کروں.اور پھر اس نام کا اس وجہ سے بھی مخفی رہنا ضروری ہے کہ تا ہر وہ شخص جو اس خط کو
پڑھے وہ گویا اس میں اپنے آپ کو ہی مخاطب خیال کرے اور اس کی طبیعت اس مخفی اثر کو قبول
کرنے کے لئے تیار ہو جائے جو خدا کے ازلی قانون کے ماتحت ایک دل سے دوسرے دل
کی طرف جاتا ہے.ان مختصر الفاظ کے ساتھ میں محترمی چوہدری صاحب کی اس مفید تصنیف
کو احباب کے سامنے پیش کرتا ہوں.فقط
خاکسار
14 / امان 1319 اعش
مطابق 14 مارچ 1940ء
10
مرزا بشیر احمد
قادیان
Page 11
شملہ
16 مئی 1939ء
بسم الله الرحمن الرحيم
عزیزم
نحمده ونصلى على رسوله الكريم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جب ہم لوگ اس دنیا سے گذر جائیں گے تو ہماری ذمہ داریاں تم پر اور تم سے بھی
چھوٹی عمر کے عزیزوں کے کندھوں پر ڈالی جائیں گی اور دنیا کی افتاد اور رفتار کو دیکھتے ہوئے
میں اندازہ کرتا ہوں کہ تم لوگوں کی ذمہ داریاں ہماری ذمہ داریوں سے کہیں بڑھ کر ہوں گی.اگر تم ان ذمہ داریوں کو پورے طور پر ادا کرو گے تو ہماری روحیں بھی خوش ہونگی اور آنے والی
نسلیں بھی تمہیں مبارک گردانیں گی.اور تمہارا نام روشن ہوگا اور زندہ رہیگا اور سب سے بڑھ
یہ کہ تم خود خدا تعالیٰ کے حضور مقبول ہو گے اور اس کی رحمت میں داخل کئے جاؤ گے.جیسے تمہاری ذمہ داریوں کا ایک حصہ تمہاری آئندہ نسلوں سے متعلق ہوگا ویسے ہی
ہماری بعض ذمہ داریاں تمہارے متعلق ہیں.میں چاہتا ہوں کہ اس تحریر کے ذریعہ ان
ذمہ داریوں کے ایک حصہ سے سبکدوش ہو جاؤں.ومــاتـوفيـقــى الا بالله العلى
العظيم-
زندگی کا نازک مرحلہ
تم اس وقت اپنی زندگی کے ایک بہت نازک مرحلہ پر ہو اور ہم سب اپنے اپنے
حالات کے مطابق اس مرحلہ میں سے گذر چکے ہیں.ہمیں اس مرحلہ میں سے گذرتے وقت
11
Page 12
اپنی مشکلات کا احساس تھا اور اگر اس وقت کوئی ہمدردانہ ہاتھ ہماری مدد کے لئے بڑھایا جاتا تو
ایک طرف ہمارے دل جذبہ شکر سے لبریز ہو جاتے اور دوسری طرف زندگی کے کئی گوشے
جو اس وقت اندھیرے اور بھیا نک نظر آتے تھے ہمارے لئے روشن اور خوشگوار ہو جاتے.لیکن جب ہم خود ان مراحل سے گذر چکے تو ہم نے ان مشکلات کو نظر انداز کر دیا.اور اب
جب ہماری آئندہ نسل پر آہستہ آہستہ وہی زمانہ آرہا ہے تو ہمیں ان کی مشکلات کی طرف کوئی
توجہ نہیں اور ہماری طرف سے ان کے ساتھ نہ ہمدردی کا اظہار کیا جاتا ہے نہ مدد کا ہاتھ بڑھایا
جاتا ہے.میں آج اس کوشش کو شروع کرتا ہوں کہ اس
کوتاہی کا ازالہ کیا جائے میں نہیں جانتا
کہ میں اس کوشش میں کامیاب ہو سکوں گا لیکن بہر حال ایک تو میں نے اپنی بساط کے مطابق
کوشش کر لی ہوگی اور دوسرے کم سے کم تمہاری طبیعت میں یہ احساس پیدا ہوگا کہ تمہارے
عزیزوں میں سے کسی نہ کسی کو تو تمہاری آئندہ زندگی سے متعلق گہری فکر ہے.پیشتر اس کے کہ میں اس تمہید کو ختم کروں میں تم سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ تم اس
تحریر کو محض ایک ذہنی لطیفہ سمجھ کر نظر انداز نہ کر دینا بلکہ سنجیدگی اور توجہ کے ساتھ اس پر غور کرنا
اور اس کے عمل کرنے والے حصوں پر عمل کرتے چلے جانا.جو اعتماد میں نے تمہارے فہم اور
دانش پر اس کے لکھنے میں کیا ہے اس اعتماد کے مستحق ہونے کا ثبوت تم اس تحریر پر فکر کرنے اور
اس پر عمل پیرا ہونے سے دے سکتے ہو.اور اگر تمہیں اپنی ترقی اور اپنی زندگی کو ایک عمدہ
اسلوب پر چلانے کی اتنی ہی فکر پیدا ہو جائے جس قدر مجھے تمہارے متعلق ہے تو پھر میری فکر
اس یقین میں بدل جائے گی کہ تم اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحم سے اور اس کی عطا کی ہوئی توفیق
سے ضرور اپنی زندگی کے مقصد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے.سب سے پہلے اس امر کو ذہن نشین کر لو کہ زندگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت
بڑی خلعت اور ایک بہت بڑا انعام ہے اور اس لئے اس کا بہت احترام اور اکرام لازم ہے.یہ کھیل نہیں.عبث فعل نہیں.اس کا مقصد بہت بلند ہے اور اس مقصد کو پالینا دائمی خوشی اور
12
Page 13
راحت کو حاصل کر لینا ہے.اس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے سب سے ضروری شے انسان
کے دل کے اندر امنگ اور امید اور بشاشت کا موجود ہونا اور قائم رہنا ہے اور سب سے
خطرناک شے جو لازمی طور پر انسان کو اس مقصد سے محروم کر دیتی ہے وہ مایوسی اور نا امیدی
ہے جس سے ہر حال میں بچنا چاہئے.دور سے
یقین جانو کہ اس وقت تم دو عالیشان دروازوں کے سامنے کھڑے ہو.اور تمہارے
اختیار میں ہے کہ چاہو تو دائیں دروازے میں داخل ہو جاؤ اور چاہو تو بائیں میں.اگر تم نے
دائیں دروازے کو چنا تو تو تم ڈیوڑھی سے گزر کر جو کسی قدر تاریک ہے اور جس میں سے
گذرنا ہمت اور استقلال اور حوصلہ چاہتا ہے جلد ایک روشن باغ میں داخل ہو جاؤ گے جس کی
روشیں اور سبزہ اور پھول اور فوارے دل لبھانے والے ہیں اور جس کے پھل تازہ اور شیریں
اور صحت افزا اور دل و دماغ کو فرحت بخشنے والے ہیں.خدا کرے کہ تم اسی دروازے کا
انتخاب کرو.لیکن اگر خدا نخواستہ تم نے بائیں دروازے کا انتخاب کیا تو گو بظاہر اس دروازے
سے
ملحق ڈیوڑھی دوسری ڈیوڑھی کی نسبت زیادہ روشن اور پر شوکت ہے اور اس کے اندر عمدہ
تصاویر اور نقش اور بت نظر آتے ہیں لیکن ڈیوڑھی سے آگے نکل کر اندھیرا اور بادل اور بجلی اور
گرج اور بھیا نک نظارے اور ہیبت ناک اور خونخوار جانور ہیں.اس کا پانی کڑوا اور بد بودار
اور گندے جراثیم سے پُر ہے اور اس کے پھل سڑے ہوئے اور بدمزہ اور زہریلے
اور پُر ہلاکت ہیں.اس کی تمام وسعت کے اندر کہیں بھی امن اور سکون اور راحت نہیں بلکہ
اس کی تمام فضا خوف اور بیماری اور موت کی فضاء ہے.خدا کرے تمہارا دل اس ڈیوڑھی میں
داخل ہونے کی طرف مائل نہ ہو.13
Page 14
یہ انتخاب تمہارے لئے اس وقت بہت آسان ہے.چاہئے کہ تم ابھی سے یہ انتخاب
کرو اور پھر استقلال کے ساتھ اس پر قائم رہو.کیونکہ جس قد ر التو تمہارے انتخاب میں ہوگا
اسی قدرتمہاری زندگی میں مشکلات کا اضافہ ہوتا جائے گا.بظاہر تو تم دائیں دروازہ کو انتخاب کر چکے ہو لیکن کیا تمہارا دل بھی اس انتخاب میں
شامل ہے اور اس کی تصدیق کرتا ہے؟ اور حوصلہ اور ہمت اور بشاشت کے ساتھ تمہیں اس
ڈیوڑھی میں داخل ہونے کا مشورہ دیتا ہے اور استقلال کا وعدہ کرتا ہے؟
17 مئی
زندگی کا مقصد
زندگی کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس مقصد کے حصول کے کیا ذرائع ہیں؟
واضح ہو کہ تمام زندگی جس میں انسانی زندگی بھی شامل ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت خلق کا
ظہور ہے.مگر زندگی کے مختلف مراحل پر انسان اللہ تعالیٰ کی مختلف صفات کے ظہور کا مورد ہوتا
ہے اور ان سے فائدہ اٹھاتا ہے.ہر وہ شے جس میں احساس ہے اور جس میں ترقی کا مادہ ودیعت کیا گیا ہے زندہ ہے
خواہ وہ جمادات میں سے ہو یا نباتات میں سے ہو یا حیوانات میں سے ہو اور خواہ اجرام فلکی
میں سے ہو.تمام مخلوقات کے لئے ترقی کا ایک آخری نقطہ مقرر ہے.اور اس نقطہ تک پہنچنے کے
لئے جس قسم کے احساسات اور قومی کی ہر نوع مخلوقات کو ضرورت ہے اسی قسم کے احساسات
اور قومی اس کے اندر شروع سے رکھ دیئے گئے ہیں.اور اسی قسم کی طاقتیں اس کے اندر شروع
سے موجود ہیں اور زمین اور آسمان میں ایسے تغیرات کا انتظام کیا گیا ہے جو ان قومی اور
طاقتوں کو مناسب حال میں ترقی دینے کے لئے ضروری ہیں اور اس ترقی میں ممد ہو سکتے ہیں.14
Page 15
لیکن تمام قسم کی مخلوقات کے لئے تدریجی ترقی کا قانون مقر ر ہے.یعنی یہ ترقی آہستہ آہستہ اور
درجہ بدرجہ ہوتی ہے اور کئی ہزار سال کے عرصہ میں جاکر ایک دور ترقی کا مکمل ہوتا ہے.صانع قدرت اور مصور عالم چونکہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا اس لئے اس نے جلدی کو
کہیں جگہ نہیں دی وہ تو وقت اور زمانے کا بھی مالک ہے اور ہر شے پر حاکم ہے.اسے جلدی
کی ضرورت نہیں.جلدی کی محتاج وہ ہستیاں ہوتی ہیں جن پر موت آنے والی ہو یا جو ایک
حالت سے دوسری حالت کی طرف جلد منتقل ہو جانیوالی ہوں.اور جن کے لئے ضروری ہو کہ
وہ وقت کی ایک مقررہ حد کے اندر ایک کام کو پورا کرلیں یا ایک خاص نتیجہ پیدا کر لیں.امر الہی
ہر شے جو معرض وجود میں آئی ہے اس کی پہلی کڑی خدا تعالیٰ کا حکم ہے.یعنی اگر ہم
کائنات سے متعلق کھوج لگا نا شروع کریں کہ فلاں چیز کہاں سے پیدا ہوئی اور فلاں کہاں
سے تو ہم کھوج لگاتے لگاتے ایک ایسے نقطہ پر پہنچ جائیں گے کہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ اس سے
آگے بس امرالہی ہی ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں.چنانچہ سائنس دانوں نے جو کھوج لگانا
شروع کیا تو پہلے تو کہا کہ تمام مادہ نہایت ہی باریک ذرات سے بنا ہے اور ان باریک
ذرات کا جب آپس میں جوڑ ہوتا ہے تو اس جوڑ کی ترکیب اور ہیئت کے لحاظ سے مختلف شکلیں
مادہ کی بنتی جاتی ہیں.پھر جب سائنس دان مادہ کی گنہ دریافت کرتے کرتے ذرات سے
آگے بڑھے تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ ذرات مجموعہ ہیں نہایت لطیف بجلی کی مانند طاقت
اور کشش رکھنے والے بلبلوں کا جو نہایت تیزی سے ایک دوسرے کے گرد چکر لگاتے رہتے
ہیں.اور بوجہ اس کشش کے جو ایک دوسرے کے لئے ان کے اندر رکھدی گئی ہے.بعض ان
میں سے ایک دوسرے کے ساتھ ایسا جوڑ اور رشتہ قائم کر لیتے ہیں کہ وہ مل کر ذرات بن
جاتے ہیں.سائنس والے تو شاید بہت عرصہ میں جا کر اس سے آگے بڑھیں گے لیکن جو
15
Page 16
تعریف انہوں نے ان بلبلوں کی کی ہے اور جو اشارات انہوں نے انکی حقیقت سے متعلق
کئے ہیں ان سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اس سے آگے اب یہی مرحلہ رہتا ہے کہ وہ یہ تسلیم
کر لیں کہ تمام مادہ کی ابتداء ایک قادر ہستی کے ارادہ کے اظہار سے ہوئی.گویا سائنس بھی
اب دبی زبان سے تسلیم کرنے لگ گئی ہے کہ تمام مادہ کی خلق امر الہی سے ہوئی ہے.ترقی کے دور
جیسا میں اوپر بیان کر چکا ہوں ہر ذرہ میں اللہ تعالیٰ نے خاص خاص صفات ودیعت
کی ہیں جن کے مطابق وہ ترقی کی اہلیت رکھتا ہے اور مناسب اسباب اور حالات میسر آنے
پر ان کے مطابق ترقی کر سکتا ہے.مثلاً بعض ذرات میں ایسی صفات رکھدی گئی ہیں کہ وہ پتھر
بن سکتے ہیں لیکن اپنی ذات میں تدریجی ترقی کرتے ہوئے پتھر سے آگے نہیں بڑھ سکتے.بعض ہیرے بن سکتے ہیں، بعض موتی، بعض کوئلہ.پھر بعض میں ایسی صفات رکھدی گئی ہیں
کہ وہ سونا چاندی، لوہا، تانبا وغیرہ بن سکتے ہیں.بعض میں ایسی صفات رکھی گئی ہیں کہ وہ
حشرات الارض اور سانپ ، بچھو، چوہے بن سکتے ہیں.بعض میں ایسی صفات رکھی گئی ہیں کہ
وہ ہر قسم کی سبزی اور اناج اور درخت اور پھل بن سکتے ہیں اور بعض کے اندر مختلف قسم کے
جانور بننے کی صفات ہیں اور بعض میں ازل سے ہی انسان بننے کی صفات رکھدی گئی ہیں.یہ تو ایک زنجیر مختلف قسم کی ترقیات کے دوروں کی ہے پھر ایک اور قسم کی ترقی کا دور بھی
ساتھ ساتھ جاری ہے.مثلاً زمین کے ذرات اور سورج کی روشنی اور گرمی اور چاند کے نور اور
ہواؤں کے اثرات اور بارش کی تازگی سب نے مل کر سبزی یا پھل کی شکل میں ظہور کیا.ادھر
اسی قسم کے اثرات کے تحت جانور بنا.انسان بنا.اب اس سبزی یا پھل کو کسی جانور یا انسان
نے کھا لیا تو اس کے بعض اجزا جانور یا انسان کی ہستی کا جزو بن گئے اور انکے اندر حیواناتی یا
انسانی صفات پیدا ہو گئیں.یا جانور کو انسان نے اپنی خوراک بنایا تو ویسی ہی تبدیلی اس جانور
کے اجزاء میں پیدا ہوئی اور اس کے بعض اجزاء نے انسان کے اجزاء کی شکل اختیار کرلی.16
Page 17
غرض تم اگر اس کا ئنات پر غور کرو تو دیکھو گے کہ کیسے ہر شے اپنے اپنے حلقہ کے اندر امرالہی
کی تکمیل میں مصروف ہے اور کیسی کیسی خوشنما شکلیں زندگی کی مختلف انواع میں پائی جاتی ہیں
اور کیسی کیسی ترتیب اور جوڑان مختلف انواع کا آپس میں ہے.یہ گونا گوں قسم کی زندگی اور کائنات کے مختلف شعبے جن کا ہم ملاحظہ کرتے ہیں اور وہ
بھی جو ہمارے ظاہری جو اس کے ملاحظہ سے نہیں گذرتے ان سب کا مرکزی نقطہ انسان
ہے.گویا اس تمام کائنات کے وسیع محل کے اعلیٰ سے اعلیٰ کمرے اور سامان انسان کے
استعمال اور اس کی ترقی کے لئے تیار کئے گئے ہیں.گو خود انسان کی پیدائش بھی ہزاروں
صدیوں کے دوران میں اسی رنگ میں ہوئی ہے جیسی باقی حیوانات کی.لیکن اس تمام پیدائش
کی اصل غرض انسان کی پیدائش اور تکمیل ہے اسی لئے انسان اشرف المخلوقات کہلایا.عام طور پر کہا جاتا ہے کہ انسان مٹی اور پانی سے پیدا کیا گیا.یہ اس رنگ میں درست
نہیں کہ مٹی اور پانی سے ایک پورا انسانی بت بنایا گیا.اور پھر اس بت کے اندر انسانی روح
پھونک دی گئی البتہ یہ اس رنگ میں درست ہے کہ انسان کی پیدائش کا سلسلہ مٹی اور پانی سے
شروع کیا گیا اور گو اس حالت سے لیکر انسان بننے تک کئی دور اس پر سے گذرے لیکن اس مٹی
اور پانی کے خمیر میں جو اہلیت رکھی گئی تھی وہ انسان ہی بنے کی تھی.چنانچہ یہ مخلوق پہلے نہایت
کمزور حالتوں میں سے گذر کر پھر حیوان کامل کے دور میں داخل ہوئی اور پھر حیوان ناطق اور
عاقل کے دور میں.اور اس مرحلہ پر اس نے بشر کی صورت اختیار کر لی اور اس حالت میں اس
پر بہت لمبا عرصہ گذر گیا.اور جب بشر کی ذہنی اور دماغی ترقی اس حالت تک پہنچ گئی کہ وہ
الہام الہی کا متحمل ہو سکے تو پھر اس دور کے مکمل ترین انسان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی
نازل ہوئی اور چند سادہ تمدنی اور معاشرتی احکام اس پر نازل کئے گئے اور اسے اور اس کے
کنبہ اور قوم کو ان احکام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی ہدایت کی گئی اور وہ انسان آدم کہلایا.لیکن در اصل نسلِ انسان کی ابتدا اس آدم سے نہیں ہوئی.بلکہ اس حالت سے شروع ہوئی
جب وہ ادنیٰ حالتوں سے ترقی کرتے ہوئے بشر کی حالت تک پہنچ گیا ( اس مضمون پر حضرت
17
Page 18
طریقہ اسیج نے پچھلے سالانہ جلسے کے موقع پر ایک مفصل تقریر فرمائی تھی.جب وہ تقریر چپ
جائے تو تمہیں توجہ کے ساتھ اس کا مطالعہ کرنا چاہئے.اور اس کے ساتھ ہی حضور کی اس تقریر
کا بھی جو حضور نے 1937ء کے سالانہ جلسہ پر فرمائی تھی اور جو انقلاب حقیقی“ کے نام سے
چھپ چکی ہے).انسان کے مٹی سے پیدا کئے جانے میں ایک یہ اشارہ بھی ہے کہ اس کی سرشت نرم مٹی
کی طرح بنائی گئی ہے.یعنی انسان کی طبیعت بیرونی اثر قبول کرتی ہے اور جس طرف اور جس
طرح اس کو ڈھالا جائے یہ ڈھالی جا سکتی ہے اور جس طرح نرم مٹی پر جونقش ہم چاہیں جما سکتے
ہیں اسی طرح فطرت انسانی بھی نقش قبول کر سکتی ہے اور اس سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ
انسان کی سرشت کے اندر لا انتہا ترقی کی استطاعت اور طاقت رکھی گئی ہے.گوانسان کی پیدائش کی ابتداء پانی اور مٹی سے ہوئی لیکن ابتدائی حالتوں سے گذر کر
جب اس کے حیوان کامل کی شکل اختیار کرنے کا دور قریب آیا تو انسان کی پیدائش نطفہ سے
شروع ہوئی اور گویا میاں بیوی اور کنبہ اور قوم اور تمدن اور معاشرت کی بنیاد رکھی گئی اور
آہستہ آہستہ پھر اس نے انسان کی شکل اختیار کی.انسانی روح کی پیدائش
یہ تو مختصر طور پر انسان کی جسمانی پیدائش کا خاکہ ہے لیکن انسان کی ایک پیدائش اس
سے بھی بڑھ کر اور اس سے کہیں اعلیٰ ہے اور وہ اس کی روح کی پیدائش ہے.جیسے اس ابتدائی
پانی اور مٹی میں انسانی خواص شروع سے ہی رکھدیئے گئے تھے اور ترقی کرتے کرتے آخر اس
سے انسان ہی پیدا ہونا تھانہ کہ کوئی اور شے یا جانور.اسی طرح اس ابتدائی پانی اور مٹی میں وہ
خواص اور صفات اور استعدادیں بھی رکھی گئی تھیں جن سے انسانی روح پیدا ہوئی تھی.گو
جیسے جسمانی شکل کی تکمیل کیلئے ہزاروں صدیاں مقدر تھیں ویسے ہی انسانی روح کی پیدائش کا
18
Page 19
زمانہ بھی ابھی بہت بعید تھا لیکن انسانی روح اس پانی اور مٹی میں اسی رنگ میں موجود تھی جیسے
گلاب کے پھول کی مہک اور گلاب کا عطر باغ کی مٹی میں موجود ہوتا ہے.رُوح کی پیدائش کی ابتدائی کڑی بھی مادہ کی ابتدائی کڑی کی طرح امر الہی ہی ہے گو
اس کے علیحدہ ظہور کے لئے ایک خاص وقت معین ہے.جب بچہ ماں کے پیٹ میں ایک
خاص حد تک نشود نما پا چکتا ہے تو ایک مہک یا عطر کے طور پر اسی میں سے اس کی رُوح پیدا کی
جاتی ہے.اور ایک نئی خلقت اور نئی زندگی اس کو عطا ہوتی ہے پھر اپنے وقت پر یہ جسم و جان کا
مرکب ایک علیحدہ اور الگ ہستی کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے اور اس ظہور کو عرف عام میں پیدائش
کہتے ہیں.جانوروں اور انسان کی روح میں بڑا فرق یہ ہے کہ انسان کی رُوح میں اپنے خالق
سے قرب حاصل کرنے کی تڑپ اور استعداد رکھی گئی ہے جو یا تو جانوروں کی روح میں مفقود
ہے یا وہ ایسی کمزور ہے کہ نہ ہونے کے برابر ہے.زندگی کی انواع
اب یہاں ٹھہر جاؤ اور زندگی کی مختلف انواع اور اقسام پر غور کر وکس قدر رنگارنگ کی
ی مخلوق ہے.کیا کیا طاقتیں اور استعدادیں مختلف قسم کی مخلوق میں رکھی گئی ہیں کیسی ترتیب ہے
کیا حسن اور دلفریبی ہے اور کیا کیا فوائد ہر قسم کی مخلوق کے ساتھ وابستہ ہیں اور یہ تو ایک نہایت
سرسری معائنہ اور پڑتال ہے.ہرفن کے ماہرین جب اس تمام مخلوق کے خواص پر غور کرتے
ہیں تو ان کی عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں.ایک جسم انسانی ہی کو لیکر غور کرو.اس کی طاقتوں اور
استعدادوں کی انتہا نہیں.جسم کے ہر حصہ کا دوسرے کے ساتھ رشتہ اور جوڑ اور ہر حصہ کے
اندر اپنے فرائض کے پورا کرنے کی طاقت اور استعداد.اور اسی کے مطابق اس کی بناوٹ
اور اس کے خواص.جلد ہی کو دیکھو یہ کس قدر رزم اور لچکدار اور ساتھ ہی کس قدر مضبوط اور
19
Page 20
سردی اور گرمی کا مقابلہ کرنے کی طاقت اپنے اندر رکھتی ہے.کیسے کامل طریق پر جسم کی
حفاظت کرتی ہے.کتنے لاکھوں کروڑوں سوراخ اس میں ہیں جو اس کی نرمی اور لچک کا
باعث ہیں، جو پسینہ کو باہر نکالتے ہیں لیکن خون کو باہر نکلنے نہیں دیتے.پھر جلد کے ساتھ
بالوں اور ناخنوں کا تعلق اور ہزاروں ہزار تفاصیل اور پھر جلد کے ساتھ وابستہ کروڑوں نالیاں
جو خون کو ادھر سے اُدھر پہنچاتی ہیں.پھر انسانی جسم کے اندر رنگارنگ کی تفاصیل اور انتظام اس
قدر باریک اور پیچیدہ کہ دنیا کے بڑے سے بڑے کارخانہ میں بھی ان کی مثال نہ ملے گی.اور پھر یہ تمام نظام کسی وحدت اور یکجہتی اور پھرتی کے ساتھ کام کرتا ہے اس کا اندازہ تم خود
کر لو تمہیں ایک ضرورت محسوس ہوتی ہے.تمہارا دماغ اس سے متعلق حکم جاری کرتا ہے، یہ
حکم اعصابی مرکزی دفتر کو پہنچتا ہے.وہ اس پھرتی سے اسکو جسم کے کناروں تک پہنچا تا اور
اس پر عمل کرواتا ہے کہ تمہیں خود بھی محسوس نہیں ہوتا کہ اس قدر مراحل سے تم گذرے ہو.بس
تمہارے دل میں خواہش پیدا ہوئی اور تمہارے اعضاء نے حالات کے مطابق یہ خواہش
پوری کردی.اگر تم غور کرو تو تمہارے اندر ایک پورا جہان بستا ہے.اپنے دل اور اس کے
احساسات پر غور کرو.اپنے دماغ اور اس کی کیفیات اور تخیلات کا مطالعہ کرو.دل میں کیا
درد، کیا حسرت، کیا پریشانیاں، کیا لطف ، کیا خوشی ، کہیں ہمدردی کا جذبہ، کہیں غیرت، کہیں
انتقام کی خواہش، کہیں بجز کہیں انکسار، کہیں محبت، کہیں مخالفت، پھر تخیلات میں وہ وسعت
اور وہ رنگینیاں کہ سبحان اللہ اور یہ سب غیر ماڈی باتیں ہیں.ماڈی باتیں کھانا پینا، دوڑ نا کودنا،
کھیلنا، تیرنا ہضم کا فعل ، بھوک پیاس ، عمدہ نظاروں کا دیکھنا، خوشبوئیں سونگھنا، عمدہ لباس پہننا
وغیرہ یہ سب کچھ الگ.تمہارے والدین عزیز، دوست ، واقف ، ہم جماعت، پروفیسر، عام
ملنے والے، ہر ایک اپنے اپنے وہم میں سمجھتا ہے کہ تم ایسے ہو، ایسے ہو.تمہارے اندر فلاں
صفت ہے، فلاں خوبی ہے فلاں حسن ہے، فلاں خامی ہے، فلاں نقص ہے.لیکن تم اپنے دل
میں خوب جانتے ہو کہ تم وہ نہیں ہو جو لوگ تمہیں سمجھتے ہیں.اول تو ہر ایک کی نگاہ میں تمہاری
ایک الگ تصویر ہے اور پھر اپنی نگاہ میں تم کچھ اور ہی ہوتی کہ جب تم آئینہ میں دیکھتے ہو تو
20
Page 21
حیرت سے خیال کرتے ہو کیا میں وہی ہوں جسے میں دیکھ رہا ہوں.نہیں یہ تو میں نہیں ہوسکتا.میرے ذہن میں تو اپنی اور ہی تصویر ہے..تمہاری اپنی الگ دنیا ہے.الگ تختیل کا عالم ہے.الگ قلبی کیفیات ہیں.کسی اور کو
ان میں دخل نہیں.مگر اس حد تک جس حد تک کہ تم خود کسی کو اجازت دو لیکن ہے یہ کہ ایک پورا
عالم اور اس جذبات اور کیفیات کے جہان کے خود ہی راہ نما ہو.خود ہی محافظ اور نگہبان ہو.اب تم اندازہ کرو کہ تمہاری ذمہ داری کس قدر وسیع اور کس قدر بھاری ہے اور یہ کس قدر
ضروری ہے کہ تم اس ذمہ داری کے سب پہلوؤں کو شناخت کرلو اور پورے علم اور فکر کے بعد
زندگی کی شاہراہ پر گامزن ہو.اور اس کے خطرات سے بچتے ہوئے اس عالم کو حفاظت اور
سلامتی کے رستہ پر چلاتے جاؤکتی کہ اپنے مقصد کو پالو.انسان پر خدائی انعامات
غور کرو تمہارا سفر کہاں سے شروع ہو ا تھا اور کن مراحل سے تم گذر چکے ہو؟ تم پہلے
برقی بلبلوں کی شکل میں معرض وجود میں آئے.پھر ذرات میں تبدیل ہوئے.پھر پانی اور
مٹی میں منتقل ہوئے پھر درجہ بدرجہ تم بڑھے.بشر بنے پھر آدم بنے.پھر کئی نسلیں انسانی
گذریں تب بالآخر حضرت مسیح ناصری کے زمانہ کے انیس سو اور اکیس سال بعد تمہاری ہستی کا
الگ وجود دنیا میں قائم ہوا.تمہارے لئے زمین بنائی گئی اور اس کے تمام خزانے مہیا کئے
گئے.سورج بنایا گیا اور اسے روشنی اور گرمی دی گئی.چاند کومنو رکیا گیا.آسمان اور ان کے
ستارے بنائے گئے.زمین کو اس کے محور پر گھومنے کا حکم ہو ا.رات اور دن ، گرمی اور سردی،
دھوپ اور سایہ، پہاڑ، دریا، سمندر، جھیلیں ، درخت، پھل، سبزه، اناج، جانور، پرندسب پیدا
کئے گئے.ہوا میں چلائی گئیں.بخارات بنے.بادل تیار ہوئے.خشک زمینوں اور وادیوں
پر بر سے.غرض زندگی کے قیام اور انسانی ترقی کے سب سامان مہیا کئے گئے پھر انسان نے
21
Page 22
نسلاً بعد نسل دماغی.اخلاقی اور روحانی ترقی کی.تمدن قائم ہوا.حکومتیں قائم ہوئیں.قوانین بنے.حفاظت کے سامان تیار کئے گئے.علوم کا چرچا ہوا.ایجادیں ہونے لگیں.جہاز بنے.ریلیں چلائی گئیں.موٹریں ایجاد ہوئیں ہوائی جہاز اڑنے لگے.تار اور ٹیلیفون
اور لاسلکی پیغام رسانی اور ریڈیو میسر آئے اور یہ سب کچھ اس لئے ہوا کہ تا بیسویں صدی میں
تمہارے لئے آرام کا سامان ہو.تعلیم کا سامان ہو.دماغی.اخلاقی اور روحانی ترقی کے
سامان ہو اور پھر ان سب سامانوں سے بڑھ کر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ خود اپنے برگزیدوں سے
کلام کیا اور بنی نوع انسان کی اعلیٰ اخلاقی اور روحانی ترقی کے لئے ہدایات نازل فرمائیں.نوح پر اور ابراہیم پر اور موسی" پر اور مسیح پر اور زرتشت پر اور کنفیوشس اور بدھ پر اور کرشن پر
اور رام چندر پر اور ہزاروں لاکھوں اپنے دیگر پیاروں اور برگزیدوں پر اور پھر ان سب کے
سردار اور اپنے محبوب محمد مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم پر اور پھر حال کے زمانہ میں اپنے پیارے احمد
علیہ الصلوۃ والسلام پر تا تمہیں خدا تعالیٰ کی رضا معلوم کرنے میں کسی قسم کی دقت نہ ہو.اور تم
اس تلاش میں بھولے بھٹکے سر گردان نہ پھرتے رہو اور اس تلاش میں ہی اپنی زندگی نہ کھو بیٹھو.تم تباؤ کونسی نعمت ہے جو تمہارے لئے مہیا نہیں کی گئی ؟ کونسا سامان ہے جو تمہیں میسر
نہیں آیا؟ اور یہ سب کچھ اس لئے کہ تم اپنی زندگی کو اس کے کمال تک پہنچا سکو.اور خوب یاد
رکھو کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری ترقی بھی ویسی ہی درکار اور پسند اور محبوب ہے جیسے کسی اور انسان
کی.اگر تم چاہو تو تم اپنے تئیں اللہ تعالیٰ کے اتنا ہی قریب کر سکتے ہو اور اس کی محبت کے اسی
قدرمورد ہو سکتے ہو جس قدر کوئی اور.اور یہ سب انعامات اور سامان ویسے ہی شخصی اور ذاتی
طور پر تمہارے لئے پیدا کئے گئے ہیں جیسے کسی اور کیلئے.اب تم اندازہ کرو کہ تمہاری زندگی
کس قدر قیمتی شے ہے.یہ کتنا بڑا انعام ہے.یہ کس قدر قابل قدر ہے.اس کا کس قدر بلند
درجہ ہے.اور تم کس قدر بھاری اور عظیم اور اعلیٰ امانت کے امین بنائے گئے ہو!
غور کرو اور سوچو کہ تم اس نظام ارضی و سماوی کے مرکزی نقطہ ہو.اشرف المخلوقات ہو.تمہیں اور تمہاری جنس کو وہ قومی، وہ طاقتیں، وہ استعدادیں عطا کی گئی ہیں جو باقی
22
Page 23
حصہ مخلوقات کو عطا نہیں کی گئیں.اور باقی حصہ مخلوقات کو تمہاری اور تمہاری جنس کی خدمت پر
مامور کیا گیا ہے.تمہیں احسن تقویم پر بنایا گیا ہے یعنی لا انتہا ترقی کے لئے جو قومی اور طاقتیں
ضروری تھیں وہ تمہیں دی گئی ہیں اور جو سامان اس ترقی کے لئے ضروری تھے وہ مہیا کئے گئے
ہیں.سو چاہئے کہ تمہارا دل خوشی سے لبریز ہو جائے اور تمہارا دل اور تمہارا دماغ اور تمہاری
روح اپنے خالق کے سامنے سجدہ میں گر جائیں.اور تم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھڑے اور
لیٹے ہوئے ان باتوں پر غور کرو اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرو.اور اس کا شکر کرو اور تمہارے دل کی
تمام کیفیات خوشی اور بشاشت کی کیفیات ہوں اور مایوسی اور نا امیدی تمہارے پاس بھی نہ
پھٹکیں.اور تمہیں اپنے خالق ورب کی قدرتوں پر پورا ایمان ہو.اور تمہارا تمام بھروسہ اور
تو گل اسی پر ہو اور اس کے ساتھ محبت اور وفا اور استقلال کا تم پختہ عہد باندھو اور صرف اسی
سے تمہیں خوف ہو اور وہی تمہارا مدعا اور مقصد اور محبوب ہو.19 مئی
زندگی کا کمال
زندگی کا مقصد کیا ہے؟ انسانی زندگی کا کمال یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی صفات کا
نقش اپنی ہستی پر جمائے.اس طور پر کہ اس کی اپنی ہستی بالکل اس نقش کے سایہ میں آجائے
اور کوئی حصہ یا کو نہ اس کا اس الہی سایہ سے باہر نکلا ہوا نہ رہے.گویا وہ اپنی ہستی میں
اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر بن جائے.اسی حالت کے کمال کا نام عبودیت یعنی اللہ تعالیٰ کا عبد
بننا ہے.چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا
لِيَعْبُدُون یعنی میں نے بڑے اور چھوٹے سب قسم کے انسانوں کو اس لئے پیدا کیا ہے کہ وہ
میرے عبد بن جائیں.یعنی میری صفات کے مظہر بن جائیں.اور اسی مقصد کو رسول اللہ
سورة الذاريات - آیت 57
23
Page 24
صل الله
نے یوں بیان فرمایا ہے تَخَلَّقُوْا بِاَخلاق اللهِ.یعنی اپنے تئیں اللہ تعالیٰ کے
اخلاق اور صفات سے مزین کرو.اور اسی حالت اور تعلق کو یوں بھی بیان کیا گیا ہے کہ
فطرت صحیحہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو اپنا محبوب بنائے اور پھر اس کی شدت محبت کا تقاضا یہ
ہوگا کہ وہ محبوب کامل کی صفات اپنے اندر پیدا کرے اور جب ان صفات کو انسانی کمال کی حد
تک وہ اپنے اندر پیدا کر لے گا تو وہ خود اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جائے گا.اور یہی آخری مقصد
حیات انسانی کا ہے اور یہی انسانی زندگی کا کمال ہے.معرفت الہی کے لئے صفات الہی کا علم ضروری ہے
اس مقصد کے حصول کے لئے لازم ہے کہ انسان
کو اللہ تعالیٰ کی صفات کا علم ہو اور وہ
بار باران صفات پر غور کرتا رہے اور ان کے ظہور کے مواقع اور ان کے اثرات کا مطالعہ کرتا
رہے تا اللہ تعالیٰ کے جبروت اور تقدس اور اس کی اعلیٰ قدرتوں کا نقش اس کے دل میں بیٹھتا
چلا جائے.اور آخر اس کے کامل جلال اور جمال کے جلوہ سے انسان اس حد تک گداز اور
بے تاب ہو جائے کہ نہ اس کی اپنی کوئی مرضی رہے اور نہ اپنی کوئی خواہش اور اس کا ہر ذرہ اسی
محبوب حقیقی کی راہ میں فدا ہو جائے.اللہ تعالیٰ کی صفات کا علم نہایت وسیع ہے.اور گہری معرفت اور شناخت کو چاہتا ہے.اور سچ تو یہ ہے کہ اصل معرفت اللہ تعالیٰ اور اس کے بندہ کے درمیان ایک راز ہے جسے الفاظ
میں بیان کرنا محال ہے.لیکن پھر بھی ایک انسان کے لئے جو اس راہ پر قدم زن ہونا چاہتا ہے
پہلا مرحلہ یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا علم ایک علم کے طور پر حاصل کرے اور اسے
اپنے ذہن اور فکر کا جزو بنائے اور اس سے فائدہ اٹھا کر معرفت کی راہوں پر گامزن ہو.24
Page 25
ہمارا خدا
اللہ تعالیٰ وہ وراء الورا اور لطیف در لطیف ہستی ہے جس کے امر سے ساری کائناتوں کا
سلسلہ شروع ہوا اور جاری ہے.اس کی قدرت اور اختیار کی انتہا نہیں.وہ اپنی ذات میں اکیلا
ہے.نہ وہ خود جنا گیا اور نہ وہ جنتا ہے.وہ اپنی ذات کے قیام کے لئے کسی مدد یا سہارے کا
محتاج نہیں.اسکے احاطہ قدرت اور اختیار سے باہر کوئی شے نہیں.اور اسکی ذات کے بغیر کوئی
ش خود بخود قائم نہیں.سب اشیا اپنے قیام کے لئے اس کے سہارے کی محتاج ہیں.کائنات
کے قیام اور ترقی کے لئے اس نے ہر شے میں خواص رکھے ہیں اور ہر حصہ کائنات کو بعض
قوانین کا پابند کیا ہے لیکن اسے یہ قدرت ہے کہ وہ ان خواص کو زائل کر دے یا انہیں بدل
دے یا ان میں ایزادی کر دے.اور اسی طرح اسے قدرت ہے کہ قوانین کے اجراء کا بعض
حالتوں میں التواء کر دے گو اپنی سنت سے متعلق اس کا وعدہ ہے کہ وہ اس میں تبدیلی نہیں
کرتا.مثلاً یہ کہ اسے قدرت ہے کہ وہ ایک مردہ کو زندہ کر دے اور پھر اسے اس دنیا کی زندگی
عطا کرے لیکن اس کا فرمان ہے کہ وہ ایسا نہیں کریگا تا بنی نوع انسان اس کی مقرر کردہ سنت
کے مطابق ہی ترقی میں کوشاں ہوں.لیکن بعض دفعہ وہ خارق عادت طور پر اپنے بندوں کے
لئے نشان دکھلاتا ہے جو کبھی تو کشف کے رنگ میں ہوتے ہیں اور کبھی مکالمہ کے طور پر.گوان
میں پھر بھی کسی قدر پہلو اخفا کا رہتا ہے.جیسے قرآن کریم میں ذکر آتا ہے کہ حضرت ابراہیم کو
ان کے دشمنوں نے آگ میں ڈال دیا لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کے ماتحت آگ انہیں کوئی
تکلیف یا نقصان نہ پہنچا سکی.اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے بارش کر کے یا تیز ہو چلا کر عین
وقت پر آگ ٹھنڈی کر دی.یا مثلاً بھوک یا پیاس کا خاصہ ہے کہ وہ کھانے اور پینے سے بجھتی ہیں.لیکن بعض دفعہ
اللہ تعالیٰ کا اپنے پیاروں کے ساتھ ایسا سلوک ہوتا ہے کہ بغیر مادی خوراک یا پینے کی اشیاء
کے وہ ان کے اس قدرتی تقاضے کو اس طور پر ٹھنڈا کر دیتا ہے کہ گویا انہوں نے واقع میں کچھ
25
Page 26
کھایا یا پیا ہے.یا مثلاً یہ کہ گوتمام مادہ خدا ہی کے امر سے پیدا ہو الیکن ہماری جسمانی آنکھوں
کے سامنے مادہ ہی کی ایک حالت بدل کر دوسری حالت پیدا ہوتی ہے.مگر بعض دفعہ اللہ تعالیٰ
یوں بھی قدرت نمائی کرتا ہے کہ بظاہر بغیر ایسی تبدیلی کے ایک مادی چیز بغیر ظاہری مادی
اسباب کے پیدا ہو جاتی ہے.جیسے حضرت مسیح موعوڈ کے کرتے پر چھینٹے پڑنے کا واقعہ ہے کہ
گو ایک حصہ اس کا کشف تھا لیکن اس کشف کے ایک حصہ کے اثرات ظاہری اور مادی
صورت میں بھی نظر آئے اور قائم رہے اور ہم نے اپنی آنکھوں سے انہیں دیکھا.غرض اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی بات انہونی نہیں.وہ ہر شے اور ہر بات پر قادر ہے.گواس کا عام طریق یہی ہے کہ جب وہ کوئی کام کرنا چاہتا تو اس کے ظاہری اسباب میں
تبدیلی کا حکم صادر فرماتا ہے.وہ تبدیلی ایسی ہوتی ہے کہ صاحبانِ بصیرت
کو اللہ تعالیٰ کا ہاتھ
اس میں صاف جلوہ گر دکھائی دیتا ہے.لیکن جن لوگوں کے دلوں میں مرض ہوتا ہے اور جو اپنی
روحانی بینائی کھو چکے ہوتے ہیں وہ ایسی تبدیلیوں اور انقلابات کو بھی ظاہری اسباب کے
قدرتی نتائج ہی شمار کرتے ہیں.ہم اللہ تعالیٰ کو کسی اور ہستی پر قیاس نہیں کر سکتے.اس کے مانند کوئی اور شے یا ہستی
نہیں.ہماری زبانوں کی وسعت محدود ہے اس لئے ہم مجبور ہوتے ہیں کہ تشبیہ اور استعارہ
کے طور پر اللہ تعالیٰ کے لئے بھی وہی الفاظ استعمال کریں جو ہم انسانوں کے لئے کرتے
ہیں.لیکن وہ الفاظ اپنے عام معانی اور مطالب کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات پر
پورے طور پر چسپاں نہیں ہو سکتے اسلئے اس کی ذات اور صفات کی وسیع سے وسیع تعریف کے
بعد بھی ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ " یعنی کوئی شے اس کے مانند نہیں.مثلاً وہ
کلام کرتا ہے لیکن ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس کی زبان ہے یا ہونٹ ہیں یا منہ ہے یا یہ کہ وہ اپنے
کلام کو اپنے کسی بندہ تک پہنچانے کے لئے ہوا کا محتاج ہے.وہ باریک سے باریک اور
پوشیدہ سے پوشیدہ چیزوں کو دیکھتا ہے لیکن ہم نہیں کہہ سکتے کہ اسکی آنکھیں ہیں.وہ انسان
سورة الشورى - آیت 12
26
Page 27
کے دل کی دھڑ کنے کی آواز کو بھی سنتا ہے لیکن ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس کے کان ہیں.اس قسم کی حد بندیاں صرف ہمارے ساتھ متعلق ہیں.اللہ تعالیٰ کی ذات ان سے
بہت بلند ہے.مثلاً مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب، دن اور رات ، روشنی اور اندھیرا، ہفتے،
مہینے، سال، صدیاں.حتی کہ وقت اور زمانہ یہ سب کچھ انسان اور اس دنیا کی حد بندیاں
ہیں.اور یہ سب نتیجہ ہیں زمین اور چاند اور سورج اور ستاروں وغیرہ کے آپس کے تعلقات
کا.اور جب یہ سب اللہ تعالیٰ کی خلق ہیں تو ان کے تعلقات کے نتائج بھی اس کی خلق ہیں.اور وہ ان سب کا خالق اور ان پر حاکم ہے.نہ کہ ان میں سے کسی کا پابند.وہ وقت اور زمانے
سے باہر ہے اور ان سے بلند.اسی طرح وہ ہر ایک قسم کے انسانی معیار اور اندازہ سے بلند
ہے.لمبائی اور چوڑائی.بار یکی اور موٹائی.بلندی اور پستی اور اوپر نیچے.سردی اور گرمی اور
دور اور نزدیک ، اپنے عام معانی میں انسانی اصطلاحیں ہیں جن کا ان مادی حالات کے ساتھ
تعلق ہے جو حیات انسانی کو گھیرے ہوئے ہیں مگر اللہ تعالیٰ کی ذات ان سب سے آزاد اور
بالا ہے اور اس لحاظ سے ہم اس کی ذات کا قیاس ان حدود پر نہیں کر سکتے.لیکن وہ ہر جگہ اور ہر
وقت موجود ہے.گو اس کی ذات مقام اور وقت کی قید سے آزاد ہے.وہ زمانہ اور وقت کے
شروع ہونے سے بھی پہلے تھا کیونکہ زمانہ اور وقت اسی کے پیدا کئے ہوئے ہیں.وہ ہر مقام
کے اندر بھی ہے اور باہر بھی ہے.کیونکہ جگہ اور مقام اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں.ہمارے
حواس اس کو محسوس نہیں کر سکتے کیونکہ وہ لامحدود اور غیر مادی اور لطیف در لطیف ہے.مثلاً
ہماری آنکھیں اسے دیکھ نہیں سکتیں لیکن اس کی صفات کے ظہور کو دیکھ سکتی ہیں.وہ اس قدر
لطیف ہیں کہ ہمارے ذہن اس کا اندازہ نہیں کر سکتے.وہ اس قدر وراء الوراء ہے کہ ہمارا ہم
اس کے قیاس سے عاجز ہے.لیکن ساتھ ہی وہ اس قدر قریب بھی ہے کہ ہمارے اپنے
خیالات بھی ہمارے اسقدر قریب نہیں ہیں.ہر خوبی بدرجہ اتم اس میں ہے اور اس کی ذات
ہر عیب اور نقص اور کمزوری اور خامی اور کمی سے پاک ہے.بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ہر خوبی نکس
ہے اس کی کسی نہ کسی صفت کا.اور ہر نقص یا عیب یا کمزوری نتیجہ ہے اس امر کا کہ اس کی کسی نہ
27
Page 28
کسی صفت کے پر تو کے سامنے انسان نے کوئی حجاب پیدا کر لیا ہے.وہ ہمیشہ زندہ اور ہمیشہ
قائم ، ہمیشہ بیدار ہے، کیوں کہ نیند اور ستی غفلت نام ہیں ان حالتوں کے جن میں بعض
صفات کے عمل میں کمی یا تعطل واقع ہو جاتا ہے اور اس کی ذات تو ہر وقت قائم ہے اور اس کی
صفات ہر وقت جاری ہیں.توحید باری
اب میں چند خاص صفات الہیہ سے متعلق کچھ لکھتا ہوں تا کہ ان صفات کے بعض
پہلو تمہارے دل پر نقش ہو جائیں.سب سے پہلی صفت اللہ تعالیٰ کی جس پر اسلام میں بہت
زور دیا گیا ہے تو حید ہے.یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں ایک ہے اور اپنی صفات میں بھی
ایک ہے.یعنی کوئی اور ہستی نہ اس کی ذات میں شریک ہے اور نہ بلحاظ ان کی کمیت اور کیفیت
کے اس کی صفات میں شریک ہے.صرف وہی ایک پرستش کے لائق ہے.یعنی اس لائق ہے
کہ ہم اس کی رضا کو ہر رنگ میں اپنے اوپر حاکم کریں اور اس کی صفات کا نقش اپنی ہستی پر
جمائیں اور ہر خوبی اور نیکی اور قدرت اور انعام کا اصل منبع اسے ہی یقین کریں اور اسی سے
سب کچھ طلب کریں اور صرف اسی کا خوف ہمارے دل میں ہو اور اسی کی محبت میں اپنی تمام
خوشی پائیں.توحید ہی سے کائنات میں امن قائم ہے ورنہ اگر معبودوں کی کثرت ہوتی تو ہر
جگہ مقابلہ اور فساد ہی فساد ہوتا اور انسانوں کے اختلافات اور تنازعات اور فسادات تو الگ
رہتے مختلف خداؤں کی باہمی جنگ ہی ختم ہونے میں نہ آتی.پھر تو حید ہی کے نتیجہ میں انسان کی بھی عظمت قائم ہوئی.ورنہ جو لوگ تو حید کے قائل
نہیں وہ کہیں دریاؤں کو پوجتے ہیں.اور کہیں سمندروں کو کہیں پہاڑوں کی چوٹیوں کو اور
کہیں غاروں کو.کہیں پتھروں کو اور کہیں درختوں کو کہیں بادلوں کو اور کہیں بجلی کو.کہیں چاند
کو اور کہیں ستاروں کو.کہیں سورج کو اور کہیں جانوروں کو.اور اس پوجنے سے غرض یہ ہے کہ
28
Page 29
ان اشیاء سے فائدہ حاصل کریں یا ان کے شر سے محفوظ ہوجائیں حالانکہ ان چیزوں کو
اختیار نہیں کہ کسی کو فائدہ دیں یا نقصان پہنچائیں.یہ سب چیزیں تمام کی تمام انسان کے
فائدہ کے لئے پیدا کی گئی ہیں.اور اس کی خدمت پر مامور ہیں اور کوئی انسان خواہ وہ کتنی ہی
طاقت رکھتا ہو دوسرے انسانوں
کو حقیقی فائدہ یا نقصان پہنچانے کی قدرت نہیں رکھتا.جب
انسان ان چیزوں کو پوجتا ہے تو اس کے دل پر ان چیزوں کا خوف اور رعب قائم ہو جاتا ہے
اور وہ در حقیقت ان کی کنہ دریافت کرنے اور ان سے فائدہ اٹھانے سے محروم ہو جاتا ہے.اس کی مثال تو ایسی ہی ہو جاتی ہے جیسے کوئی متمول شخص جس کا مکان ہر قسم کے سامانوں سے
آراستہ ہو اور جس میں بجلی کی روشنی اور سیکھے اور طرح طرح کے انتظامات ہوں اور جس کے
بہت سے خادم ہوں جو ہر وقت اس کی اور اسکے مہمانوں کی خدمت میں لگے رہتے
ہوں اور جس کے مکان کے ارد گرد وسیع باغ ہو ، جس میں قسم قسم کے خوشنما پھول ہوں اور
جھاڑیاں اور پیر ہوں اور عمدہ روشیں اور چھوٹی چھوٹی نہریں ہوں جن میں فو آرے چلتے ہوں
اور پانی بہتا ہو اور جابجا سنگ مرمر کے تخت بنے ہوئے ہوں اور کثرت سے پھلوں والے
درخت ہوں ، اپنے کسی دیہاتی دوست کو مہمان بلائے جو پہلے ان چیزوں سے زیادہ واقف
نہ ہو.اور ایک سقیم الحال شخص ہو جو تنگی سے گزارہ کرتا ہو.اور جب وہ اس متمول شخص کے
ہاں مہمان جائے تو اس کے باوردی خادموں
کو دیکھ کر گھبرا جائے اور خیال کر لے کہ یہ شخص
افسر اور حاکم اور شاید دیوتا ہو.اور جب ان میں سے کوئی آگے بڑھے کہ اس کی کوئی خدمت
بجالائے تو یہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑے اور گھٹنوں کے بل کھڑا ہو جائے.یا سجدہ میں گر
جائے.اور عاجزی سے کہنے لگے.”اے طاقتور دیوتا! تو مجھ پر رحم فرما.اور میرے قصور
معاف کر دے اور مجھ پر عنایت کی نظر ڈال.اور پھر جب کسی کمرہ میں داخل ہو اور دیکھے کہ
بجلی کا فانوس کیسے خوشنما طور پر روشن ہے اور جگمگا رہا ہے تو وہیں سجدہ میں گر جائے اور ویسے ہی
اس سے پرارتھنا کرنے لگے.اور جب بڑے بڑے آئینوں میں اس فانوس کی روشنی کو دیکھے
تو آئینہ کے سامنے گر جائے.اور جب محسوس کرے کہ بجلی کا پنکھابظاہر خود بخود چل رہا ہے اور
29
Page 30
اس سے خوشگوار ٹھنڈی ہوا پیدا ہورہی ہے تو اس کی طرف منہ اٹھا کر اور ہاتھ باندھ کر دعا میں
مصروف ہو جائے.اور پھر باغ میں جائے اور پھولوں اور جھاڑیوں اور درختوں اور فواروں
وغیرہ سے متعلق بھی ایسی ہی حرکات کرے.اور اتفاق سے کسی کو ٹیلیفون پر بات کرتے سُن
لے تو بالکل متوحش ہو جائے.اور اگر کہیں کوئی ہوائی جہاز آسمان کی فضا میں سے گذرتا ہوا
دیکھ لے تو سمجھے کہ اب میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے کیونکہ شاید موت کا دیوتا آسمان
سے اتر نے لگا ہے.اس سے بھی بدتر اور زیادہ مضحکہ انگیز حالت ان لوگوں کی ہے جو سورج
اور چاند اور ستاروں اور دریاؤں اور سمندروں اور پہاڑوں اور جانوروں وغیرہ کی پرستش
کرتے اور ان کو خیر اور شر کا مالک گمان کرتے ہیں.حالانکہ ان سب کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی
خدمت کے لئے پیدا کیا ہے.غرض تو حید اللہ تعالیٰ کے صحیح مقام اور درجہ کو واضح کرتی ہے اور انسان کو اس کے اصل
مقام پر لا کھڑا کرتی ہے اور اس کے دل سے ماسوئی اللہ کے خوف کو دور کرتی ہے.اور ہر قسم
کے علوم کے دروازے اس کے لئے کھولتی ہے اور اس کے دماغ کو جلا بخشتی ہے اور قسم قسم کی
ایجادوں اور اختر اعوں اور ترقیات کا راستہ کھولتی ہے.جب انسان کو یقین ہو جاتا ہے کہ
کائنات کے تمام پُرزے اور ساز وسامان اس کی خدمت اور ترقی کیلئے اللہ تعالیٰ نے پیدا کئے
ہیں تو وہ ان سے متعلق غور کرتا ہے اور ان کے اصل فوائد کی تلاش میں مشغول ہو جاتا ہے.اور
اس پر ہر روز نئے علوم کا انکشاف ہوتا ہے.پھر تو حید ہی کے نتیجہ میں انسانوں کے درمیان مساوات قائم ہوتی ہے.جب سب
انسانوں کو ایک ہی خالق نے پیدا کیا ہے اور وہی سب کا پالنے والا اور ترقی دینے والا ہے اور
ہر شے پر قدرت رکھتا ہے اور ہر شے کا مالک ہے اور صرف وہی ایک پرستش کے لائق ہے اور
اسی سے سب فوائد اور انعام اور ترقیات جاری ہوتی ہیں تو پھر کسی انسان کو دوسرے پر
بالذات تفوق نہیں رہتا اور ہر ایک کے لئے اللہ تعالیٰ کے قرب کے دروازے یکساں کھل
جاتے ہیں.اور انسان ہونے کی حیثیت سے سب انسان برابر شمار ہونے لگتے ہیں.اور
30
Page 31
گورے اور کالے اور زرد اور بادامی اور حبشی کی تفریق مٹ جاتی ہے.پھر نہ کوئی برہمن رہتا
پیسے نہ چھتری نہ ولیش نہ شودر.ہاں جان پہچان کی خاطر ملکی اور قومی تقسیمیں رہ جاتی ہیں.لیکن
یہ قسیمیں عزت اور ذلت کا معیار نہیں ہوتیں.عزت کا اصل معیار خدا تعالیٰ کی محبت اور اس کا
خوف بن جاتے ہیں.رب العالمين
اللہ تعالیٰ کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ رب العالمین ہے.یعنی تمام کائنات کو ادنیٰ
حالت سے تبد ریج ترقی دے کر اعلیٰ حالت کی طرف لے جاتا ہے.کسی ایک خاص قوم یا
گوت یا ملک یا نسل کو نہیں بلکہ سب کو.اس صفت کے ماتحت بھی سب ملکی اور قومی اور نسلی
امتیاز مٹ گئے.سورج، چاند، ستارے، آسمان ، بادل، بارش، دریا،سمندر، پہاڑ غرض دنیاوی
ترقی کے سب سامان سب کے لئے ہیں.اور اسی طرح نبوت، رسالت، رویا، کشوف ، وحی،
الہام، روحانی ترقی کے سب سامان بھی سب کے لئے تھے اور ہیں.اس ایک ہی اس صفت
سے ثابت ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول بصورت وحی اور الہام سب قوموں اور
ملکوں میں ہؤا ہے.رحمن
پھر وہ رحمن ہے.یعنی اس نے ہماری ترقی کے لئے جس قد ر سامان ضروری تھے وہ
بغیر ہماری طرف سے کوئی عمل صادر ہونے کے بلکہ پیشتر اسکے کہ ہماری طرف سے کوئی عمل
صادر ہوتی کہ ہماری پیدائش سے بھی پیشتر مہیا فرمائے.زمین بنائی اور اس میں مختلف قسم
کے خواص اور طاقتیں رکھیں.سورج چاند ستارے اور آسمان بنائے.اور ان میں قسم قسم کے
31
Page 32
خواص اور استعداد میں اور طاقتیں رکھیں.ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کیا.پھر خود ہمیں ہر
قسم کے قومی عطا فرمائے.بینائی دی.شنوائی دی.گویائی دی.سونگھنے کی طاقت دی.ذائقہ
دیا.چھونے کی حس عطا کی ، دماغ اور فہم دیا.ہاتھ پاؤں دیئے.غرض قسم قسم کی طاقتیں عطا
فرمائیں.ہوا پیدا کی.پانی پیدا کیا.اناج پیدا کیا.جانور پیدا کئے جو خوراک کے بھی کام
آئیں اور جن سے ہم سواری وغیرہ کا کام بھی لے سکیں.غرض لا انتہا خزانے پہلے سے ہی
ہماری ترقی کے سامانوں کے مہیا فرما دئیے.رحیم
پھر اس کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ رحیم ہے.یعنی ہمارے اچھے اعمال کا ہمیں بہتر
سے بہتر بدلہ بصورت عمدہ نتائج کے دیتا ہے اور تھوڑے تھوڑے اور محدود اعمال کا وسیع سے
وسیع اور لامحدود بدلہ عطا فرماتا ہے.مالک یوم الدین
پھر اُس کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ مالک یوم الدین ہے.یعنی وہ اعمال کی جزا اور سزا
کے وقت کا مالک ہے.جرم پر چاہے تو مناسب سزا دے اور چاہے تو بخش دے اور
اعمال حسنہ کا جس قدر بڑھ کر چاہے بدلہ دے.وہ پابند نہیں کہ جرم کی ضرور سزا دے یا پوری
سزا دے.اور پابند نہیں کہ نیک اعمال کا صرف برابر کا ہی بدلہ دے، جتنے گنا چاہے بدلہ
دے.32
Page 33
مجیب الدعوات
پھر اللہ تعالیٰ کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ پکارنے والے کی پکار کوسنتا ہے.یعنی اپنے
بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے.اور یہ صفت بھی باقی صفات کی طرح ہمیشہ جاری رہے.گو
افسوس ہے کہ خود مسلمانوں کے ایک کثیر طبقہ میں بھی اس صفت پر رسمی سا ایمان باقی رہ گیا
ہے.حالانکہ اس صفت کا ظہور ہی سب سے مؤثر اور قومی ذریعہ بندے اور اس کے خالق کے
درمیان رشته مضبوط کرنے کا ہے.بلکہ قرآن کریم نے تو اس صفت کے ظہور کو اللہ تعالیٰ کی
ہستی کے ثبوت میں پیش فرمایا ہے اَمَّنْ يُجِيْبَ الْمُضْطَرَّاذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوء
یعنی تم یہ بتاؤ کہ حالت اضطراب میں جب تم آشانہ الٹی پر گر جاتے ہو اور اس کے
رحم کو جوش
میں لاتے ہو اور وہ تمہارے کرب اور بے چینی اور بے چارگی پر رحم فرما کر تمہاری تکلیف کو دور
کرتا ہے تو پھر تم کیسے اس کا انکار کر سکتے ہو؟ اور مضطر کی دعا کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ نے تقویٰ اور
اعمال صالحہ کی شرط بھی نہیں رکھی.یعنی جب انسان حقیقی اضطراب کی حالت میں تضرع اور
خشیت کے ساتھ اس کی دہلیز پر گر جاتا ہے اور پکھلتے ہوئے دل کے ساتھ اس کے رحم کا
طالب ہوتا ہے تو وہ ضرور رحم فرماتا ہے اور اپنے بندہ کی پکار کوسنتا ہے اور اس حالت میں وہ یہ
نہیں دیکھتا کہ یہ انسان عام حالات میں کس قدر نا فرمان اور سرکش ہے.ہاں اپنے فرمانبردار
اور مسکین اور فروتن بندوں کے ساتھ جو اس کے ساتھ حقیقی تعلق قائم کرتے ہیں اور اس کی
رضا جوئی میں لگے رہتے ہیں اور اس کی خوشنودی کے مقابلہ میں سب کچھ بیچ سمجھتے ہیں وہ
بہت بڑھ چڑھ کر سلوک کرتا ہے.اور اس کا ان کے ساتھ کچھ عجیب رشتہ قائم ہو جاتا ہے جس
کی حقیقت کو بس وہی پورے طور پر سمجھ سکتے ہیں گو اس کے آثار اور نتائج دوسرے لوگوں کے
دیکھنے میں بھی آتے ہیں.ظاہر بین نگاہ میں خواہ ایسے لوگ کوئی بڑی حیثیت نہ رکھتے ہوں
لیکن اللہ تعالیٰ کے دربار میں وہ مقبول ہوتے ہیں اور ہر ایک کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا الگ الگ
سورة النمل - آیت 63
33
Page 34
سلوک رحمت اور شفقت اور محبت کا ہوتا ہے.جیسے ایک بزرگ نے فرمایا ہے
اے ترا با ہر کسے رازے دگر
ہر گدا را بر درت نازے دگر
رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے چہرے غبار
آلود اور بال پریشان ہوتے ہیں (یعنی بظاہر کوئی بڑی حیثیت نہیں رکھتے اور دیکھنے میں
مفلوک الحال نظر آتے ہیں) لیکن جب وہ خدا پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ کہہ دیتے ہیں کہ فلاں
بات یوں ہوگی تو پھر خدا تعالیٰ کو ان کی اتنی قدر منظور ہوتی ہے کہ وہ ویسے ہی کر دیتا ہے.تو اللہ تعالیٰ کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ دُعاؤں کو سنتا ہے.یہ صفت انسان کے لئے
کس قدر مژدہ جانفزا ہے اور کس قدر تستی اور اطمینان اور جرات اور حوصلہ انسان کے اندر
پیدا کرنے والی ہے.ایک مومن سخت سے سخت تکلیف کی حالت میں یا بڑے سے بڑے
خوف یا خطرہ کے وقت اس یقین سے تسلی پاتا ہے کہ میرا رب ہر وقت میرے ساتھ ہے اور
جب بھی میں اسکی طرف جھکوں وہ میری طرف متوجہ ہوتا ہے اور میری پکار اور گریہ وزاری کو
سنتا ہے اور میری دعاؤں کو قبول کرتا ہے.پھر مجھے کس چیز کا خوف ہو سکتا ہے.قرآن کریم
میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے إِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيْبٌ أُجِيْبُ دَعْوَةَ
الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ یعنی جب میرے بندے میرے متعلق تجھ سے دریافت کرتے ہیں تو
انہیں بتا دے کہ میں پاس ہی ہوں.جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کوسنتا
اور قبول کرتا ہوں.اب اس سے بڑھ کر اطمینان اور تسلی اور کیا ہوسکتی ہے کہ وہ قادر ہستی جس
کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے اور کوئی چیز اسکے احاطہ قدرت سے باہر نہیں اور سب کچھ
اس کے لئے ممکن ہے اور کوئی بات اس کے لئے انہونی نہیں.وہ ہم سے کہتا ہے گھبراؤمت
میں ہر وقت پاس ہوں، مجھ سے مانگو میں دونگا.میں ہر دکھ کو سکھ سے اور ہر تکلیف کو راحت
سے بدل سکتا ہوں اور میرے انعاموں اور فضلوں کی کوئی حد بندی نہیں کر سکتا.سورة البقرة - آيت 187
34
Page 35
قبولیت دعا
اس لئے یہ نکتہ اپنے دل میں نقش کر لو کہ ہمارا خدا زندہ اور قادر خدا ہے اور وہ یقیناً یقیناً
دعاؤں کو سنتا ہے.ہمارا وہ آتا ہے اور مالک ہے اور عالم الغیب ہے.وہ پابند نہیں کہ ہماری
ہر دعا کو اسی رنگ میں قبول فرمائے جس رنگ میں ہم دعا کرتے ہیں.ہماری نظروں کی
وسعت محدود ہے.بسا اوقات ہم نہیں جانتے کہ ہمارے لئے کونسی چیز بہتر ہے اور ہوسکتا ہے
کہ ہم ایسے امر کے لئے دعا کر رہے ہوں جو حقیقتاً ہمارے لئے مضر ہو یا ہماری ترقی میں
روک ڈالنے والا ہو.ایسی دُعا کا قبول کرنا اللہ تعالیٰ کی صفت رحم کے بھی خلاف ہوگا.کیونکہ گو
ہم نہیں جانتے مگر وہ تو جانتا ہے کہ یہ بات ہمارے لئے مضر ہے.بعض دفعہ انسان کو اپنی
بہتری اور ترقی ہی کے لئے مشکلات اور تکلیفات میں سے گذرنا پڑتا ہے اور بہر صورت جب
اللہ تعالیٰ بندے کی سنتا اور مانتا ہے تو بعض دفعہ بندے کو اپنی بھی منواتا ہے لیکن یہ حقیقت ہے
کہ اخلاص کے ساتھ دل سے نکلی ہوئی دُعا ضائع نہیں جاتی.اگر اپنے اصل رنگ میں قبول نہ
ہوگی تو کسی اور رنگ میں اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ عطا فر مائے گا.تمہیں کسی وقت بھی اس احساس سے غافل نہیں ہونا چاہئے کہ خواہ تم کیسی ہی
مشکلات میں گھر جاؤ یا کیسی ہی تکالیف کا تمہیں سامنا ہو اللہ تعالیٰ کا دربار ہر وقت کھلا ہے.تم
فوراً دوڑ کر اس کے حضور حاضر ہو جاؤ وہ ہر وقت تمہاری پناہ ہو گا اور تمہاری حفاظت کرے گا اور
تم سے محبت سے پیش آئیگا اور تم اس کی رحمتوں اور فضلوں سے حصہ پاؤ گے.افسوس که مسلمانوں نے اس زمانہ میں اللہ تعالیٰ کی اس صفت سے منہ موڑ لیا.اور عملاً
اس کے منکر ہو گئے.کس قدر بڑا انعام تھا جسے اُنہوں نے کھو دیا! بعض نے تو برملا کہہ دیا کہ
دعا تو محض انسان کے اپنے دل کو تسلی دینے کا ایک ذریعہ ہے ورنہ اس کے نتیجے میں کوئی بیرونی
اثر پیدا نہیں ہوسکتا.حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے سختی سے اس کارڈ فرمایا.اور بار بارلکھا
ہے کہ اگر تم کو دعا کے اثر پر ایمان نہیں تو میرے پاس آؤ اور قبولیت دعا کے اثر کو دیکھو.چنانچہ
35
Page 36
فرمایا:
اور پھر فرمایا
اے کہ کوئی گر دعا ہا را اثر بودے کجا است
سوئے من بشتاب بنمائم تراچوں آفتاب
مکن انکارزیں اسرار قدرت ہائے حق
قصہ کوتہ کن ہیں از ما دعائے مستجاب
ہاں
کرامت گرچه بے نام و و نشان است
بیا
بنگر
زغلمان
اس میں بھی قبولیت دعا ہی کی طرف اشارہ ہے اور پھر ہم میں سے اکثر اپنی ذاتوں
میں علی قدر مراتب دعاؤں کی قبولیت کے شاہد ہیں.الہام الہی
پھر اللہ تعالیٰ کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ اپنے بندوں کے ساتھ کلام کرتا ہے.اس
صفت سے تو آج سوائے جماعت احمدیہ کے تمام دنیا منکر ہے.یعنی اکثر لوگ یہ خیال کرتے
ہیں کہ بیشک گزرے ہوئے زمانوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ساتھ کلام کیا ہے لیکن
اب وہ کسی کے ساتھ کلام نہیں کرتا اور نہ آئندہ کر دیگا.گویا یہ لوگ خدا تعالیٰ کی اس صفت کو اب
معطل سمجھتے ہیں.اور ایک دوسرا گروہ ایسا ہے جو کبھی اس صفت کے قائل ہی نہیں تھے.اور
ان دونوں قسم کے لوگوں کے قیاس میں موجودہ زمانہ میں بہر صورت اللہ تعالیٰ کی یہ صفت
جاری نہیں حالانکہ ایسا قیاس اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق سخت بد گمانی ہے اور سچ تو یہ ہے کہ جو
لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ کلام نہیں کرتا وہ خواہ رسمی طور پر یہ
مان بھی لیں کہ کبھی وہ کلام کیا کرتا تھا، ان کے دلوں کی گہرائیوں میں اس بات پر ایمان نہیں
36
Page 37
ہوتا ور نہ یہ ہونہیں سکتا کہ جو شخص حقیقتا اللہ تعالیٰ کی صفات کا عرفان رکھتا ہو اور یہ ایمان رکھتا ہو
کہ اللہ تعالی کی ایک صفت بندوں کے ساتھ کلام کرنا بھی ہے وہ بھی یہ خیال کرے کہ اب وہ
صفت معطل ہو چکی ہے.یا مسلمان ہوتا ہو ا وہ یہ خیال رکھے کہ پہلے زمانہ میں تو اللہ تعالیٰ
اپنے بندوں کے ساتھ کلام کیا کرتا تھا لیکن امت محمدیہ سے وہ کچھ ایسا خفا ہے کہ امت محمدیہ کے
کامل سے کامل افراد کو بھی یہ شرف حاصل نہیں ہوسکتا.دراصل ایسا قیاس نہ صرف اللہ تعالیٰ
سے متعلق بدظنی ہے بلکہ انسان کی روحانی ترقی کو بھی بالکل روک دینے والا ہے.جیسے
حضرت
مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے اگر یہ سچ ہو کہ کلام الہی کا سلسلہ بند ہے تو
اللہ تعالیٰ کے عشاق تو اپنی جانیں کھو بیٹھیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان حق الیقین تک نہ
پہنچ سکے.اس لئے یقین جانو کہ اللہ تعالیٰ اب بھی اپنے پیاروں کے ساتھ ویسے ہی کلام کرتا
ہے جیسے پہلے کیا کرتا تھا.اور جوں جوں انسان
کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ بڑھتا ہے وہ اپنے
ظرف اور استعداد کے مطابق اللہ تعالیٰ کی اس صفت کا ظہور بھی دیکھتا ہے خواہ خفی طور پر ہو اور
خواه جلی طور پر اور خواہ اس صورت میں کہ اس کی مثال شبنم یا بوندا باندی کی ہو اور خواہ
موسلا دھار بارش کی شکل میں.2 مئی
خدائے غفور
ایک صفت اللہ تعالیٰ کی یہ بھی ہے کہ وہ اپنے بندوں کے گناہوں کو بخشتا ہے نہ صرف
اس طور پر کہ وہ ان گناہوں کی سزا یا بدلہ یا نقصان سے بچ جاتے ہیں بلکہ اس طور پر بھی کہ خدا
ان کے گناہوں
کو محو کر دیتا ہے کہ گویا وہ کبھی صادر ہی نہیں ہوئے تھے کیونکہ اس کو ہر چیز پر
37
Page 38
قدرت ہے اور ماضی اور حال اور مستقبل صرف انسانی حالات کے تقاضے ہیں.اللہ تعالیٰ ان
سب سے بالا اور ان سب پر حاکم ہے.غرض اس کی گونا گوں صفات میں جن کا علم قرآن کریم
کے مطالعہ سے حاصل ہو سکتا ہے اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تصانیف اور
حضرت خلیفة المسیح الثانی کی تصانیف اور تقریروں میں بہت شرح وبسط کے ساتھ
انکی تفاصیل بیان کی گئی ہیں اس کی صفات کا آپس میں با ہمی جوڑ ہے اور ہر ایک صفت کے عمل
کا الگ الگ دائرہ ہے.اور ان کا آپس میں کوئی تصادم نہیں بلکہ اتحاد عمل ہے جیسے ایک منتظم
حکومت کے مختلف محکمہ جات مختلف صیغوں اور شعبوں
کا انتظام کرتے اور ان کے متعلق احکام
جاری کرتے اور ان کی نگرانی اور پڑتال کرتے ہیں اسی طرح.لیکن اس سے بہت زیادہ وسیع
پیمانے پر اور بہت زیادہ منظم طریق سے اور کمال خوش اسلوبی سے اللہ تعالیٰ کی صفات اپنے
اپنے دائرہ کے اندر سر گرم عمل ہیں.تخلّق با خلاق الله
اب یہ سوال ہوسکتا ہے کہ انسان کس طور پر اللہ تعالیٰ کی صفات کا نقش اپنی ہستی پر
جما سکتا ہے یا کس طور پر ان صفات کا پر تو اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے؟
سو جانو کہ بعض صفات اللہ تعالیٰ کی ایسی ہیں کہ وہ اُنھیں معنوں اور اسی مفہوم میں انسان
اختیار نہیں کر سکتا جن معنوں اور مفہوم میں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں.مثلاً
اللہ تعالیٰ ایک ہے تو یہ تو انسان کے لئے جائز نہیں کہ وہ کوشش کرے کہ دنیا میں وہی اکیلا
انسان رہ جائے.یہ تو منشاء الہی کے بھی خلاف ہے اور انسانیت کو بھی ختم کر نیوالی بات ہے.خالص تو حید تو صرف اللہ تعالیٰ کی ہی صفت ہو سکتی ہے کیونکہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے
گا.اور اپنی بقا کے لئے وہ کسی اور ہستی یا کسی سہارے یا اسباب کا محتاج نہیں لیکن ایک رنگ
میں ظلی طور پر انسان اس صفت کے حصول کی کوشش کر سکتا ہے اور وہ اس حکم کے ماتحت
38
Page 39
فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ یعنی نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو.ہر انسان کو کوشش کرنی چاہئے کہ وہ اپنے جو ہر کو کمال تک پہنچائے اور اس رنگ میں یکتائی
کے حصول کی کوشش کرے جیسے حضرت خلیفۃ المسیح الثانی نے فرمایا ہے
میں واحد کا متوالا ہوں اور واحد میرا پیارا ہے
گر تو بھی واحد بن جائے تو میری آنکھ کا تارا
ہے
پھر ایک ایسی ہی صفت اللہ تعالیٰ کی صد ہونے کی ہے کہ وہ اپنی ذات میں قائم ہے اور
اسے کسی سہارے کی ضرورت نہیں.اب چونکہ انسان اور تمام دیگر جنسیں اور تمام اشیاء
اللہ تعالیٰ کے سہارے پر قائم ہیں اس لئے اس صفت کے اولین مفہوم کے رنگ میں تو انسان
صد نہیں بن سکتا.لیکن وہ یہ کوشش کر سکتا ہے کہ اس کا اصل تو کل اور سہارا صرف
اللہ تعالیٰ کی
ذات پر ہو اور اس کے سوا اور کسی پر نہ ہو.اور اسی ضمن میں یہ بات بھی آجاتی ہے کہ اس صفت
کا ایک تقاضا یہ ہے کہ انسان کسی سے سوال نہ کرے رسول اللہ ﷺ کے پاس ایک دفعہ
ایک شخص آیا اور اس نے آپ سے سوال کیا آپ نے اسے کچھ دیدیا اس نے پھر مانگا آپ
نے پھر دیا.اس نے پھر مانگا آپ نے پھر دیا.جب اس نے چوتھی بارسوال کیا تو آپ نے
فرمایا میں تمہیں ایک ایسی بات بتا تا ہوں جو ان سب چیزوں سے افضل ہے اور وہ یہ کہ اوپر کا
ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے پس سوال کی عادت ترک کرو.اس نے کہا یا رسول اللہ ! میں
عہد کرتا ہوں کہ آئندہ سوال نہیں کرونگا.بعد میں وہ شخص اچھا متمول ہو گیا.ایک دفعہ کسی
موقع پر وہ گھوڑے پر سوار تھا کہ اس کا کوڑا نیچے گر گیا.ایک شخص جو قریب تھا اس نے چاہا کہ
کوڑا اٹھا کر اس شخص کو دیدے لیکن اس شخص نے اسے خدا کی قسم دی کہ تم کوڑا مجھے اٹھا کرمت
دو.میں خود گھوڑے سے اُتر کر اٹھاؤں گا کیونکہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے عہد کیا تھا کہ
میں سوال نہیں کرونگا.اور اگر میں تمہیں کوڑا اٹھانے دوں تو گویا یہ بھی ایک قسم کا سوال ہی
ہو جاتا ہے.سورة البقرة - آيت 149
39
Page 40
بعض صفات اللہ تعالیٰ کی ایسی ہیں کہ وہ بالکل الوہیت سے مخصوص ہیں.مثلاً یہ کہ وہ
ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا.یا یہ کہ نہ اس کا باپ ہے اور نہ اس کی اولاد.ایسی صفات
کلیتہ اللہ تعالیٰ میں اور انسان میں تمیز اور فرق کرنے والی ہیں.مثلاً یہ دونوں صفات حقیقی
توحید کا نتیجہ ہیں.اسی طرح کامل توحید کے نتیجہ میں یہ بھی صفت ہے کہ اللہ تعالی پر نہ نیند آتی
ہے نہ سستی نہ غفلت.اب انسان کے لئے یہ تو ضروری ہے کہ اپنے فرائض کی ادائیگی میں
وہ ایسی کمزوریوں کو پیدا نہ ہونے دے.لیکن بشریت کے لحاظ سے ایسی حالتیں اس کے لئے
لازم بھی ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کو مدنظر رکھتے ہوئے ایسے تقاضوں کے پورا
کرنے کا خود انتظام فرمایا
ہے اور یہ اس کے انعامات میں سے ہے کہ انسان نیند اور غنودگی اور
آرام کی ضرورت محسوس کرے.کیونکہ انسان فانی ہے اور ایک فانی ہستی کے لئے لازم ہے
کہ وہ کام کرنے کے بعد آرام کرے ورنہ وہ جلد ختم ہو جائے گی.اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ میرے انعامات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جہاں میں نے دن کو روشن بنایا ہے کہ تم کام
کر سکو اور روزی مہیا کرو وہاں رات کو اندھیرا بنایا ہے تا تمہیں آرام کا عمدہ موقع میسر آئے
ور نہ تم ہلاک ہو جاتے.پاکیزہ زندگی
پھر یہ تو ظاہر بات ہے کہ انسان کے قومی اور اسکی استعداد میں اور اس کا دائرہ عمل محدود
ہیں اس لئے وہ اپنے محدود حلقہ اور دائرہ عمل کے اندر ہی ان صفات کا مظہر بن سکتا ہے اور
اللہ تعالیٰ کی صفات صرف عکسی طور پر اس کے اندر جلوہ گر ہوسکتی ہیں.مثلاً اللہ تعالی قدوس
ہے.انسان کو بھی چاہیئے کہ پاکیزگی کی راہیں اختیار کرے اور اپنے دل اور دماغ ، خیالات
اور اعمال سب کو پاکیزہ بنانے اور رکھنے کی کوشش کرے.اسلام یہ نہیں سکھاتا کہ انسان گناہ
میں پیدا ہو اور گناہ سے بچنے کی طاقت نہیں رکھتا.بلکہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کے ہر بچہ
40
Page 41
فطرت صحیحہ پر پیدا ہوتا ہے اور وہ معصوم ہوتا اور گناہ سے پاک ہوتا ہے.گویا انسانی فطرت کی
بناء پاکیزگی اور نیکی پر ہے اور بدی باہر سے آتی ہے.اور اگر ایسا ہے تو ہر انسان کی قدرت
میں ہے کہ وہ اپنے تئیں پاکیزہ رکھے اور یا اگر کسی حد تک بدی کا اثر قبول کر چکا ہے تو پاکیزگی
کی طرف لوٹ آئے.بدی کا دروازہ ہر وقت بند کیا جاسکتا ہے اور اگر انسان بدی سے بکلی
اجتناب کرے اور اللہ تعالیٰ کے قرب کی راہیں اختیار کرے اور ان پر استقامت اختیار کرے
تو پھر اللہ تعالیٰ کی اس صفت کے ماتحت کہ وہ گناہ بخشا اور ان کو جو بھی کر دیتا ہے.انسان کامل
پاکیزگی کو اختیار کر سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفت قدوسیت کا مظہر بن سکتا ہے.رسول اللہ
نے فرمایا ہے التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَّا ذَنْبَ لَهُ یعنی گناہ سے پوری پوری
تو بہ کرنے والا ایسا ہی ہو جاتا ہے کہ گویا اس سے گناہ صادر ہی نہیں ہوا.یہ کتنا بڑا مردہ ہے.اور انسان کے لئے کس قدر خوشی کا پیغام ہے اور کس قد رامنگ اور ہمت اس کے دل میں پیدا
کرنے والا ہے بخلاف اس تعلیم کے کہ اگر انسان سے خود بدی نہ بھی صادر ہو، تو پھر بھی وہ
آدم کے گناہ یا اپنی پہلی پیدائشوں کے بُرے اعمال کی پاداش میں بدی ہی میں پھنسا رہے گا.پاکیزگی میں ظاہری اور باطنی دونوں
قسم کی پاکیزگی شامل ہے.بعض لوگ خیال کر
لیتے ہیں کہ چونکہ پاکیزگی قلب سے تعلق رکھتی ہے اس لئے ظاہری پاکیزگی کی چنداں
ضرورت نہیں.اسلام اس خیال
کا موید نہیں.اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جسم اور روح کا
آپس میں گہرا رشتہ اور تعلق ہے اور روح کی حالت کا اثر جسم پر اور جسم کی حالتوں کا اثر روح پر
پڑتا ہے.اس مسئلہ کی وضاحت تو کسی اور موقع پر زیادہ موزوں ہوگی لیکن یہاں اس قدر بیان
کر دینا ضروری ہے کہ روحانی صفائی اور پاکیزگی کے لئے جسمانی اور ظاہری صفائی بھی لازم
ہے.یعنی انسان کے جسم اور لباس اور مکان اور گردو پیش کی صفائی ضروری ہے.اللہ تعالیٰ
قدوس ہے اور نظیف ہے اس لئے اس کے قرب کے حصول کے خواہشمند کیلئے لازم ہے کہ وہ
اپنے دل کو بھی پاک کرے تا وہ خدا تعالیٰ کا عرش بن سکے.اور اپنے جسم اور لباس اور مکان
اور گردو پیش کو بھی پاکیزہ اور صاف رکھے تا اس پاکیزگی اور صفائی کا اثر اس کے قلب اور روح
41
Page 42
پر بھی ہو اور وہ دیگر بنی نوع کیلئے باعث آزار نہ ہو اس لئے رسول اللہ ﷺ نے تاکیدی
احکام غسل اور مسواک اور صاف لباس اور خوشبولگانے وغیرہ سے متعلق دیئے ہیں.پھر اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے.انسان کو بھی چاہئے کہ صفت ربوبیت اپنے اندر پیدا
کرے اور اس صفت کا حلقہ تنگ نہ کرے.بلکہ جیسے اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت وسیع اور عام
ہے اور تمام کائنات پر حاوی ہے اسی طرح انسان کی صفت ربوبیت بھی عام اور وسیع
ہو.گو جیسے اللہ تعالیٰ کا سلوک اپنے بندوں کے ساتھ ان کے ظرف کے مطابق ہوتا ہے انسان
کی ربوبیت کا عمل بھی اس سے فائدہ اٹھانے والوں کے ظرف کے مطابق ہوگا.اور اس
صفت کے عمل میں آنے کیلئے ضروری نہیں کہ انسان متمول بھی ہو کیونکہ ہر شخص اپنی اپنی توفیق
کے مطابق دوسروں کی ربوبیت کر سکتا ہے اور اس سے زیادہ کا اس سے مطالبہ نہیں.پھر اللہ تعالیٰ رحمن ہے.انسان کو چاہئے کہ اپنی توفیق اور استعداد کے مطابق اپنے
اندر صفت رحمانیت بھی پیدا کرے.یعنی یہ ضروری نہیں کہ نیکی اور حسنِ سلوک کے بدلہ میں
ہی نیکی اور حسنِ سلوک کرے بلکہ خود بخود اپنی طرف سے بغیر اس کے کہ اس میں اجر یا بدلہ کا
رنگ پایا جائے بنی نوع انسان کے لئے ایسے سامان بہم پہنچائے جو ان کے آرام کا باعث
ہوں یا ان کی ترقی میں ممد ہوں.پھر اللہ تعالیٰ رحیم ہے.نیک عمل کا نیک اور بڑھ کر بدلہ دیتا ہے.انسان کو بھی چاہیئے
کہ یہ صفت اپنے اندر پیدا کرے اور نیکی اور حسنِ سلوک اور خدمت اور محنت کا عمدہ بدلہ دے
اور اس کے تناسب سے بڑھ کر بدلہ دے.پھر اللہ تعالیٰ غفور ہے.انسان
کی توبہ قبول کرتا ہے اور اس کے گناہوں اور لغزشوں کو
بخشا اور ان کو مو کرتا ہے.اور ان کے نتائج کو بھی مٹادیتا ہے انسان کو بھی چاہیئے کہ محل اور موقع
کے مناسب دوسرے انسانوں کے قصور معاف کرے اور جہاں وہ اس بات کے مستحق ہوں
معافی کے بعد ان کے قصوروں کو بھول جائے اور اپنے دل سے ان کا ثر زائل کر دے.ایک
بزرگ سے متعلق روایت آتی ہے کہ آپ کے کسی غلام سے کوئی قصور سرزد ہوا اور آپ کے
42
Page 43
چہرے پر غصہ کے آثار ظاہر ہوئے.غلام نے کہا الکاظمین الغیظ اس پر آپ کے چہرہ
سے غصہ کے آثار جاتے رہے اور آپ مسکرا دیئے.پھر اس غلام نے کہا والــعــافـيـن عـن
الناس.اس پر آپ نے فرمایا.ہم نے تمہیں معاف کیا.پھر اس نے کہا والله يحبّ
المحسنين.اس پر آپ نے ہنس کر فرمایا جاؤ ہم نے تمہیں آزاد کیا.یہ قرآن کریم کی ایک
آیت کے حصے ہیں.اللہ تعالیٰ مومنوں کی تعریف میں فرماتا ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ
وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِینَ.یعنی سچے مومن اپنے غصوں کو
دباتے ہیں اور لوگوں کے قصور معاف کر دیتے ہیں.اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے
محبت کرتا ہے.لیکن اللہ تعالیٰ عادل بھی ہے.یعنی جرم کی سزا اس کی نسبت سے بڑھ کر نہیں دیتا اور
نیک عمل کا بدلہ اس کی نسبت سے کم نہیں دیتا.پھر جہاں وہ غافر الذنب اور قابل التوب ہے وہاں شدید العقاب بھی ہے.یعنی مجرم
کو اس کے جرم کی سزا بھی دیتا ہے اور جہاں حالات
کا یہ تقاضا ہوتا ہے وہاں سخت گرفت بھی
کرتا ہے.خدا کا عدل ورحم
بعض لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی صفتِ عدل اور رحم کی حقیقت کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں سخت
ٹھوکر کھائی ہے اور انہیں ان دونوں صفات کا تقاضا پورا کرنے کی خاطر کفارہ کا مسئلہ ایجاد کرنا
پڑا ہے.اور اس عقیدہ کی تکمیل کی خاطر ایک کمزور انسان
کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا اور الوہیت میں
شریک کرنا پڑا ہے حالانکہ ان دونوں صفات میں با ہم کوئی تصادم نہیں.محض ان لوگوں کے فہم
کا قصور ہے.انہوں نے عدل کی تعریف یہ کی ہے کہ جرم کی سزا ضرور دیجائے اور پوری
سورة آل عمران - آیت 135
43
Page 44
دیجائے.مگر یہ مسیح نہیں بلکہ عدل کی تعریف یہ ہے کہ جرم کی سزا اس کی حد سے بڑھ کر نہ
دیجائے اور اچھے عمل کا بدلہ اس کی نسبت سے کم نہ دیا جائے.جرم معاف کر دینا یا اس کی سزا
میں تخفیف کر دینا عدل کے خلاف نہیں اور نہ یہ عدل کے خلاف ہے کہ اچھے عمل کا بدلہ اس کی
نسبت سے بڑھ کر یا بہت بڑھ کر دیا جائے.اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے عیسائی لوگ خود ہر
روز اپنی زندگیوں میں اسی اصول پر عمل کرتے ہیں اور اسے عدل کے خلاف نہیں سمجھتے.بلکہ
اگر وہ ایسا نہ کریں تو ضرور خیال کریں کہ حقیقی عدل پر عمل نہیں ہو رہا.اور اپنی دعا میں وہ ہر روز
کہتے ہیں کہ اے ہمارے باپ جو آسمان میں ہے! ہمارے گناہ بخش جیسے ہم ان لوگوں کو
بخشتے ہیں جو ہمارا قصور کرتے ہیں.اسلام نے اس بارہ میں یہ تعلیم دی ہے کہ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا ۚ وَمَنْ عَفَا
وَأَصْلَحَ فَأَجْرَهُ عَلَى اللهِ لا یعنی جرم کی سزا اسکی نسبت سے ہونی چاہیئے.لیکن جہاں
حالات ایسے ہوں کہ مجرم کو معاف کر دینے سے اس کی اصلاح کی زیادہ توقع ہو سکتی ہے
بہ نسبت اس کو سزا دینے کے، تو وہاں معاف کر دینا بہتر ہے اور اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ
تمہیں اس کا بہتر اجر دیگا.اب دیکھو کیسی صفائی سے ان دونوں صفات کا حلقہ مقرر ہو گیا.اور
کسی قسم کا تصادم یا مقابلہ نہ رہا اور ساتھ ہی یہ بات بھی واضح ہوگئی کہ سزا کی اصل غرض اصلاح
ہے نہ کہ محض بدلہ لینے کی خاطر دکھ اور تکلیف میں ڈالنا.گو اصلاح سے مراد صرف مجرم کی ہی
اصلاح نہیں بلکہ باقی ایسے لوگوں کی اصلاح بھی اس میں شامل ہے جو اخلاقی طور پر کمزور ہیں
اور جنہیں اگر سزا کا خوف نہ ہو تو وہ بالکل ہی نڈر ہو جائیں اور جرائم کی طرف مائل ہو جائیں.یہ ایک مختصر اور غیر مکمل سا خلاصہ ہے حیات انسانی کے مقصد کا.رسول اللہ ﷺ
نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ میری رضا کو اپنا مقصد بنالیتا ہے اور اپنی
مرضی کو میری رضا کی خاطر ترک کر دیتا ہے تو میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ
دیکھتا ہے اور اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے اور اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں
سورة الشورى - آیت 41
صلى الله
44
Page 45
جن سے وہ کام کرتا ہے اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے.اور مراد اس
سے یہ ہے کہ چونکہ ایسے بندہ کی مرضی اور اس کی نیت اور اس کا عمل سب اللہ تعالیٰ کی رضا کے
ماتحت آجاتے ہیں اور اس کے مطابق ہو جاتے ہیں اس لئے اس کا ہر فعل خدا تعالیٰ کی مرضی
کے مطابق ہو جانے کی وجہ سے ایک رنگ میں اللہ تعالیٰ ہی کا فعل ہو جاتا ہے.یہ وہ حالت
ہے جس سے متعلق کہا جاتا ہے کہ انسان نے اپنی زندگی کے مقصد کو پالیا.تعلق باللہ کا ذریعہ
اس مقصد کے حصول کے طریق کیا ہیں؟ مختصر طور پر اس طریق کو یوں بیان کیا گیا ہے
کہ انسان اللہ تعالیٰ کی رضا کو ہر بات پر مقدم کرلے.لیکن سوال یہ ہے کہ اس کی رضا کیسے
معلوم ہو؟ وہ ایک وراء الوراء اور لطیف در لطیف ہستی ہے اور انسان گو جسم کے اندر روح بھی
رکھتا ہے لیکن اول تو اس کی زندگی مادی حالات سے گھری ہوئی ہے اور پھر اس کی روح اس
مادی زندگی کے تعلقات اور علائق کی وجہ سے باوجو د لطیف ہونے کے اللہ تعالیٰ کی ہستی کے
مقابلہ میں ایک مادی جسم کی طرح کثیف ہے.ہم روزانہ زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ہم اگر ایک
عزیز دوست کی مرضی معلوم کرنا چاہیں تو باوجود اس کے کہ وہ ہماری جنس کا ہے اور ہم اس کے
گردو پیش کے حالات کو جانتے ہیں اور ایک لمبا عرصہ اس کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے اس
کی عادت اور خیالات اور جذبات سے بہت حد تک واقف ہیں ،لیکن پھر بھی جب تک وہ
خود ہمیں اپنی مرضی نہ بتائے یا کسی طریق سے خود اس کا اظہار ہم پر نہ کرے ہم وثوق سے اس
کی مرضی معلوم نہیں کر سکتے.اور اگر ہم قیاس پر انحصار کریں تو اکثر غلطی کرتے ہیں بلکہ بعض
دفعہ جب وہ خود بھی اپنی مرضی کا اظہار کر دیتا ہے تو ہم اس کے سمجھنے میں غلطی کر جاتے ہیں.پھر جب ایک ہم جنس دوست کے اور ہمارے درمیان ایسا معاملہ ہوسکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی
مرضی معلوم کرنے میں ہم کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں سوا ا سکے کہ وہ خود ہی ہم پر رحم فرمائے اور
45
Page 46
خود اپنی مرضی کا اظہار ہم پر کرے اور وہ طریق ہمیں کھول کر بتا دے جن کو اختیار کرنے سے
ہم اس کی رضا کو حاصل کر سکیں.اور ہونا بھی ایسا ہی چاہیئے کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت
انسان کے دل میں رکھدی ہے تو لازم ہے کہ وہ انسان کو وہ طریق بھی بتائے جن پر چل کر
انسان اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کر سکتا ہے.ورنہ صورت یہ ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان
کے دل میں ایک تڑپ پیدا کر دی لیکن اسے پورا کرنے کا کوئی طریق نہیں بتایا اور یہ اُس کے
رحم سے بہت بعید ہے.اس لئے جب سے انسانی دماغ اس قابل ہو ا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ محبت
کا احساس کر سکے اس وقت سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام اور وحی کا سلسلہ جاری ہے تا
انسان کو اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کی راہیں سکھائی جاسکیں.جوں جوں انسانی دماغ
ترقی کرتا گیا، الہام اور وحی کی نوعیت میں بھی ترقی ہوتی گئی.اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے
نازل ہونے والی ہدایات میں بھی وسعت پیدا ہوتی گئی حتی کہ وہ زمانہ آگیا جب انسانی دماغ
اور روح کامل شریعت اور ہدایت کے متحمل ہونے کے قابل ہو گئے اور کامل شریعت کا نزول
صلى الله
اس کامل انسان محمد مصطفے ﷺ پر ہوا جوسید ولد آدم اور اللہ تعالیٰ کا برگزید محبوب تھا.اس
کامل ہدایت نامہ کا نام قرآن کریم ہے اور اس کے اندر انسان کی اخلاقی اور روحانی ترقی کی
کامل تعلیم موجود ہے.الہام کی کیفیت
الہام اور وحی کا سلسلہ کیا ہے اور اس کی نوعیت کیا ہے؟
یہ ایک لمبی بحث ہے لیکن ایک پہلو اس کا تمہیں صفائی سے ذہین نشین کر لینا چاہیئے
کیونکہ اس سے متعلق اس زمانہ میں بہت سی غلط فہمی پیدا ہوگئی ہے.اللہ تعالیٰ کی طرف سے
انسان پر اللہ تعالیٰ کی مرضی کا اظہار کرنے کے کئی طریق ہیں.ان میں سے ابتدائی طریق تو رویائے صالحہ کا سلسلہ ہے کہ انسان مصفی خواب دیکھتا
46
Page 47
ہے اور اس کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ انسان محسوس کر لیتا ہے کہ یہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف
سے ہے اور وہ یا تو اپنی ظاہر حالت میں اور یا اپنی تعبیر کے مطابق پوری ہو جاتی ہے.اور اگر
اس میں کوئی انذاری پہلو ہوتا ہے تو یا تو دعا اور صدقہ کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ اُسے ٹال دیتا ہے
اور یا وہ پورا ہو جاتا ہے.کیونکہ انذاری خوابوں سے اللہ تعالیٰ کا منشا یہ بھی ہوتا ہے کہ اپنے
بندوں کو آگاہ کر دے تاوہ صدقہ اور دُعا اور اصلاح کی طرف متوجہ ہوں اور اگر وہ ایسا کرتے
ہیں تو بسا اوقات اللہ تعالیٰ آنے والے خطرہ کو ٹال دیتا ہے کیونکہ اس نے فرمایا ہے کہ میری
رحمت ہر شے پر غالب ہے.پھر رؤیا سے بڑھ کر کشوف کا درجہ ہے.اور کشف سے مراد یہ ہے کہ انسان نیم
بیداری یا کامل بیداری کی حالت میں ایک نظارہ دیکھتا ہے.اس طور پر کہ جیسے ایک پردہ ہٹا دیا
گیا ہے اور اس کے سامنے ایک نظارہ پیش کیا گیا ہے اور پھر وہ بھی اپنی اصل صورت میں یا
اپنی تعبیر کے مطابق پورا ہو جاتا ہے.اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ رویا یا کشف میں کسی
آنے والے وقت کی طرف اشارہ نہیں ہوتا محض اللہ تعالیٰ کی طرف سے محبت اور شفقت اور
بندہ نوازی کا اظہار ہوتا ہے جس سے دیکھنے والے انسان کی روح خوشی سے معمور ہو جاتی ہے
اور عشق الہی کی چنگاری اس کے دل میں اور تیز ہو جاتی ہے اور وہ خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول
میں پہلے کی نسبت بہت تیزی سے قدم اٹھانے لگتا ہے.اور کشف سے بڑھ کر پھر خالص الہام اور وحی کا سلسلہ ہے اور اس کی کئی اقسام ہیں.اور بعض حالتیں اس کی نسبتاً ضعیف ہیں اور بعض نہایت پر شوکت اور پر جلال ہیں.بعض دفعہ
تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک آواز سنائی دیتی ہے جیسے پردہ کے پیچھے سے کوئی شخص کلام کر رہا ہے اور
بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ گویا کوئی شخص سامنے کھڑا نظر آتا ہے جو کلام کرتا ہے.اور بعض دفعہ
براه راست الفاظ دل پر اترتے ہیں جیسے گھنٹی بجتی ہے اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ الہامی
کلام انسان کی زبان پر جاری کر دیا جاتا ہے.لیکن جو نکتہ یادر کھنے کے لائق ہے وہ یہ ہے کہ
خالص الہام یا وحی کے الفاظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں اور وہ کلام اللہ تعالیٰ کا کلام
47
Page 48
ہوتا ہے.یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ انسان کے دل میں ایک بات بجلی کی چمک کی
طرح اپنی منشا کے ماتحت ڈال دیتا ہے اور پھر وہ بات شدت سے انسان کے دل میں راسخ
ہو جاتی ہے.ایسی بات بھی الہی تفہیم یا الہامی کہلا سکتی ہے.لیکن گو وہ بات یعنی اس کا مفہوم
الہی ہوتا ہے لیکن اس کے الفاظ انسان کے اپنے ہوتے ہیں.مثلاً پرانی مذہبی کتب کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اوائل زمانہ میں انبیاء کو
وتعلم
اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہامی تعلیم زیادہ تر رویائے صالحہ یا کشوف کے رنگ میں دی جاتی تھی
اور گو انہیں الہام یا وحی کی صورت میں اللہ تعالیٰ سے ہمکلام ہونے کا شرف ضرور حاصل ہوا
ہوگا لیکن اس الہام یا وحی کے الفاظ محفوظ نہیں ہیں یا بہت کم محفوظ ہیں.لیکن جوں جوں
شریعت کی شوکت اور اس کی تفاصیل بڑھتی گئیں تصویری اور کشفی صورت سے بڑھ کر شریعت
الفاظ کی صورت میں نازل ہونے لگی.چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ میں خالص
الہام اور وحی کا پتہ چلتا ہے.اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے متعلق تو قرآن کریم میں ذکر ہے
كَلَّمَ اللهُ مُوسى تَكْلِيمًا.یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسی" کے ساتھ کلام کیا لیکن
حضرت ابراہیم اور حضرت موسے علیہا السلام پر جو کلام نازل ہو اوہ اپنے الفاظ میں محفوظ نہیں
بلکہ اس کا مفہوم ان انبیاء کے الفاظ میں اُن کی امتوں
کو پہنچایا گیا.چنانچہ گو حضرت موسی کی
امتوں پہنچایا
تعلیم کا اکثر حصہ تفصیلی طور پر موجود ہے لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ میں نہیں بلکہ زیادہ تر
حضرت موسیٰ" کے الفاظ میں ہے.قرآنی خصوصیت
لیکن رسول اللہ ﷺ پر جو کلام نازل ہو اوہ تمام تر بعینہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ میں
محفوظ ہے اور وہ قرآن کریم ہے اور اسی لئے اسے کلام اللہ بھی کہتے ہیں.دوسری مذہبی کتب
سورة النساء - آیت 165
48
Page 49
کے مقابلہ پر قرآن مجید کی یہ سب سے بڑی خصوصیت ہے کہ یہ خدا تعالیٰ کا اپنا کلام ہے اور
اُسی کے الفاظ ہیں جو رسول اللہ ﷺ پر نازل ہوئے اور جو بغیر تحریف اور تبدیلی کے محفوظ
ہیں.چنانچہ رسول اللہ ﷺ کی یہ خصوصیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی استثناء باب 18 میں
بھی بیان ہے جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے : میں ان کے ( یعنی بنی اسرائیل کے) لئے ان کے
بھائیوں (یعنی بنو اسمعیل) میں سے تجھ سا ( یعنی صاحب شریعت ) نبی بر پا کرونگا.اور اپنا
کلام ( یعنی قرآن کریم ) اس کے منہ میں ڈالوں گا اور جو کچھ میں اُس سے فرماؤں گا وہ سب
ان سے کہے گا.رسول اللہ ﷺ کے منکرین تو کہتے ہیں کہ قرآن کریم نعوذ باللہ رسول
اللہ ﷺ کی
اپنی تصنیف ہے لیکن بعض مسلمان کہلانے والے بھی اس زمانہ میں ایسے پیدا ہو گئے ہیں جو
کہتے ہیں کہ رسول اللہ یہ تھے تو اللہ تعالیٰ کے سچے نبی اور جو کچھ قرآن کریم میں درج ہے
وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر نازل ہوا لیکن قرآن کریم کے الفاظ خدا کے الفاظ نہیں بلکہ
رسول اللہ ﷺ کے الفاظ ہیں.اس سے متعلق یاد رکھنا چاہیئے کہ اول تو جب رسول اللہ
ﷺ نے فرما دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور لفظ بلفظ وہی ہے جو مجھ پر نازل ہو ا تو پھر کسی
شک اور تاویل کی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی لیکن اسکے علاوہ قرآن کریم کی عبارت کا اپنا
اسلوب بھی یہی بتاتا ہے کہ یہ خدا تعالیٰ کا کلام ہے اور یہی دعویٰ قرآن کریم میں متعدد
مقامات پر موجود ہے.پھر رسول اللہ ﷺ کا مسلمہ کلام احادیث نبوی کی صورت میں
الله
ہمارے سامنے موجود ہے اور قرآن کریم کی عبارت اور رسول ﷺ کے کلام کی خصوصیات کا
مقابلہ کرنے سے خوب واضح ہو جاتا ہے اور ہر انسان
کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ یہ دونوں کلام ایک
ہی ہستی کے کلام نہیں ہیں.رسول اللہ ﷺ کا اپنا کلام عموماً چھوٹے چھوٹے جملوں میں ہوتا
ہے جو زیادہ تر جمالی رنگ کا کلام ہے.اور اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ہلکی ہلکی خوشبو دار
بوندیں پڑ رہی ہوں اور قرآن کریم کی عبارت زیادہ تر جلالی کلام ہے اور اس کی مثال ایک
بحرز خار کی ہے جواندا چلا آ رہا ہے.49
Page 50
قرآن مجید میں کامل ہدایت ہے
اب یہ
کیسی خوشی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنا کلام ہمیں میسر ہے جس میں کامل
ہدایت درج ہے.جو شخص بھی خدا تعالیٰ سے محبت رکھتا ہو اس کے دل میں اس خبر سے کسقدر
خوشی کا ولولہ پیدا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا صحیفہ ہم میں موجود ہے اور ہم تھوڑی سی محنت سے
اسے پڑھ سکتے ہیں اور اس میں سے ہر قسم کی دماغی اور اخلاقی اور روحانی ترقی کے اصول اخذ
کر سکتے ہیں.لیکن افسوس کہ اس زمانہ میں خود مسلمانوں نے اس برکت اور ہدایت کی مشعل
کو دور کی اندھیری کوٹھڑیوں میں بند کر رکھا ہے اور اس کی روشنی سے اپنے تئیں محروم کر لیا ہے
اور اندھیرے میں ہیں.لیکن پھر بھی اس نور سے فائدہ نہیں اُٹھاتے جسے اللہ تعالیٰ نے نازل
کیا ہے.وہ پیاسے ہیں لیکن اُس چشمہ سے سیراب ہونے کی کوشش نہیں کرتے جسے اللہ تعالیٰ
نے جاری کیا ہے.وہ بھوکے ہیں لیکن اس دستر خوان کی طرف منہ نہیں کرتے جو اللہ تعالیٰ نے
ان کے سامنے بچھایا ہے.وہ مفلس ہیں لیکن اس خزانہ سے مالا مال نہیں ہوتے جو اللہ تعالیٰ
نے ان کے لئے جمع کیا ہے.آج ہٹلر کی تقریر کا اعلان ہوتا ہے تو وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر
ریسیور کے گرد جمع ہو جاتے ہیں کہ سینیں وہ کیا کہتا ہے.حالانکہ بسا اوقات اس کی تقریریں دنیا
میں بے امنی اور اضطراب اور فساد کا پیش خیمہ ہوتی ہیں لیکن خدا کی تقریر کو لوگ جزدانوں میں
بند کر کے الماریوں میں محفوظ رکھے ہوئے ہیں حالانکہ اس کے اندر امن اور ترقی اور بہبودی اور
کامیابی کی سب تفاصیل درج ہیں.اگر ایک صبح کو اخبار نہیں ملتا تو بیقرار ہو جاتے ہیں حالانکہ
اخباروں
کا اکثر حصہ بے بنیاد باتوں پر مشتمل ہوتا ہے جن کی دوسرے دن تردید ہو جاتی ہے
لیکن تمام صداقتوں کے منبع کے نزدیک بھی نہیں جاتے.جیسا کہ میں نے ابھی بیان کیا ہے قرآن کریم کامل ہدایت اپنے اندر رکھتا ہے اور
اسمیں کوئی بات ایسی نہیں جو انسان کے لئے کسی رنگ میں بھی نقصان دہ ہو کیونکہ وہ ایک ایسی
ہستی کا کلام ہے جس نے انسان کو اور کل کائنات کو پیدا کیا.وہ انسانی فطرت کی باریک سے
50
Page 51
بار یک گہرائیوں کو جانتا ہے اور خوب جانتا ہے کہ اسکے اندر کیا وساوس پیدا ہو سکتے ہیں
اور اسے کن حالات سے گزرنا پڑیگا اور کن مشکلات کا اُسے سامنا ہوگا.لیکن اس کلام کو سمجھنے
اور اس سے صحیح تعلیم حاصل کرنے اور اس تعلیم سے فائدہ اٹھانے کے لئے اس نے یہ شرط
لگادی ہے کہ اس کا مطالعہ کرنے والا پاکیزہ دل اور پاکیزہ اعمال کا انسان ہو.یہ شرط خود
قرآن کریم کے اللہ تعالیٰ کا کلام ہونے کا ثبوت ہے کیونکہ یہ اگر انسانی کلام ہوتا تو خواہ کتنا ہی
عالمانہ کلام ہوتا اس کے سمجھنے کے لئے صرف صاف فہم اور عقل صحیحہ کی شرط ہوتی.پاکیزگی
قلب اور پاکیزگی اعمال کا اس سے کچھ تعلق نہ ہوتا.لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک حقیقت ہے
کہ جن لوگوں نے محض عقل سے قرآن کریم کو سمجھنا چاہا ہے وہ اس کا صحیح مفہوم معلوم کرنے
سے قاصر رہے ہیں اور انہوں نے اس پر جلال اور پر معانی کلام سے متعلق سخت ٹھوکر کھائی
ہے.اور جن لوگوں نے پاکیز گئی قلب اور پاکیزگئی اعمال کی شرط کو پورا کرتے ہوئے اس
کلام کا مطالعہ کیا ہے ان پر اللہ تعالیٰ نے علوم روحانی کے دروازے کھول دیئے ہیں اور وہ وہ
مطالب ان پر ظاہر کئے ہیں جن پر غور کرنے سے انسان کا دل اللہ تعالیٰ کے کلام کی عظمت
سے بھر جاتا ہے.یہ خصوصیت کسی انسانی کلام کو حاصل نہیں اور نہ حاصل ہو سکتی ہے.قرآن مجید کا بڑا معجزہ
پھر قرآن مجید کا ایک بہت بڑا معجزہ یہ ہے کہ اس میں ہر زمانہ اور سب حالات کے
مطابق ہدایت اور تعلیم موجود ہے اور اسکی مثال یوں ہے کہ جیسے یہ زمین اور تمام نظام نشسی
جب سے کہ انسان کی پیدائش ہوئی اسی حالت میں چلا آیا ہے جس حالت میں کہ وہ آج
ہے.لیکن ہر زمانے میں انسان اپنے معلومات میں اضافہ کرتا اور نئے نئے خزانے دریافت
کرتا چلا آیا ہے حالانکہ یہ سب خواص اور طاقتیں شروع سے موجود تھیں صرف کوشش کی
ضرورت تھی جوں جوں انسان اُن کا کھوج لگا تا گیاوہ ظاہر ہوتی گئیں.اسی طرح خدا کا کلام
51
Page 52
بھی ساڑھے تیرہ سو سال سے موجود ہے اور اس کے اندر تمام روحانی اور اخلاقی ہدایتیں جمع
کر دی گئی ہیں.اپنے اپنے زمانہ کی ضرورت کے مطابق جوں جوں اللہ تعالیٰ کے نیک
بندے اس سے نور حاصل کر کے اس میں غور کرتے ہیں وہ زمانہ کے حالات کے مطابق اُس
میں سے ہدایت اخذ کر لیتے ہیں.اب یہ بھی ایک ایسی خصوصیت ہے جو اللہ تعالیٰ ہی کے کلام
میں ہو سکتی ہے.کسی انسان کو قدرت نہیں کہ ایسا کلام بنا سکے.ایسا کلام اللہ تعالیٰ ہی کا ہوسکتا
ہے جو عالم الغیب ہے اور جو خوب جانتا ہے کہ آئندہ کیا کیا ہونے والا ہے.حفاظت قرآن
پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں وعدہ فرمایا ہے کہ ہمیں نے اسے نازل کیا ہے اور
ہمیں اس کی حفاظت کریں گے.اور اس حفاظت کے دو پہلو ہیں.ایک ظاہری اور ایک
باطنی.ظاہری حفاظت سے تو یہ مراد ہے کہ اس کے الفاظ اور ان کی ترتیب کی حفاظت کی
جائے گی.یعنی نہ وہ ضائع ہوں گے اور نہ اُن میں تحریف کی جائے گی.چنا نچہ یہ بات
دوست دشمن کی مسلّمہ ہے کہ قرآن کریم کے تمام الفاظ اور اس کے تمام حروف اور اس کی تمام
حرکات اسی طرح اور اسی ترتیب سے محفوظ ہیں جو ترتیب رسول اللہ ﷺ کے وقت میں قائم
کی گئی تھی اور ان میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہوئی.اور آج دنیا میں قرآن کریم ہی ایک کتاب
ہے کہ اگر دنیا سے تمام کتابیں تلف کر دیجائیں تو وہ پھر بھی قائم رہے گا کیونکہ وہ اپنے
ہزاروں لاکھوں عشاق کے سینوں میں محفوظ ہے.اور باطنی حفاظت سے یہ مراد ہے کہ اس کی
اصل تعلیم محفوظ رہے گی اور ہر زمانہ کی ضروریات کے مطابق ظاہر ہوتی رہے گی.جب بھی
انسانی تاویلیں اور تفسیر میں اس کی حقیقت پر پردہ ڈال دیں گی اللہ تعالیٰ اپنے کسی برگزیدہ بندہ
کے ذریعہ اُس کی اصل تعلیم کو پھر ظاہر کر دیگا.چنانچہ یہ وعدہ بھی پورا ہو رہا ہے.انیسویں
صدی کے آخر اور بیسویں صدی کے شروع میں جس قدر انقلاب انسان کی ظاہری اور باطنی
52
Page 53
زندگی پر آیا ہے اس کی مثال پہلے زمانوں میں بہت کم ملتی ہے.ایک طرف تو ظاہری علوم نے
حیرت انگیز ترقی کی ہے اور دوسری طرف دنیا روحانیت سے بالکل غافل بلکہ بے بہرہ ہوگئی
ہے.ایسے زمانہ میں خصوصیت سے قرآن کریم کی اصل تعلیم کے احیاء کی ضرورت تھی چنانچہ
اللہ تعالیٰ کی رحمت نے یہ احیاء حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعہ سے کیا اور اس
زمانہ میں اسلام کی تازہ زندگی کی بناء حضور کے ہاتھوں ڈالی.اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی
طرف سے اس ظاہری اور باطنی حفاظت کا وعدہ اور پھر اس کے مطابق عملی انتظام ثابت کرتا
ہے کہ قرآن کریم زندہ اور قادر خدا کا کلام ہے.غرض ہمارے لئے یہ نہایت اطمینان اور خوشی کی بات ہے کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا
کلام موجود ہے اور اس زمانہ کی ہدایت کے لئے جس قد رتعلیم بھی ضروری ہے وہ اللہ تعالیٰ کے
قائم کردہ انتظام کے ماتحت ہم تک پہنچا دی گئی ہے اور اس طرح اللہ تعالیٰ کے قرب کے
حصول کے دروازے پھر ہمارے لئے کھول دیئے گئے ہیں.21 مئی
قرآن میں ترتیب
غیر مسلم معترضین کی طرف سے اعتراض کیا جاتا ہے کہ قرآن کریم کے مضامین میں
بظاہر کوئی ترتیب نہیں اور بعض دفعہ خود مسلمانوں کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ کیوں ہر مسئلہ پر
ایک ہی جگہ تمام احکام جمع نہیں کر دیئے گئے.اور اسی قسم کے اور اعتراضات عدم علم اور
عدم تدبر کی وجہ سے کئے جاتے ہیں.اول یہ سمجھ لینا چاہئے کہ قرآن کریم کی موجودہ ترتیب
بے شک اس ترتیب کے مطابق نہیں جس ترتیب پر اس کا نزول ہوا ہے لیکن یہ ترتیب ہے
رسول اللہ ﷺ کے ارشاد کے مطابق.جب کوئی آیت نازل ہوتی تھی تو رسول
کریم ﷺ
فرما دیا کرتے تھے کہ اسے فلاں سورۃ میں فلاں جگہ رکھا جائے اور یہ ترتیب الہی منشاء کے
53
Page 54
مطابق ہوتی تھی.قرآن کریم کے نزول کے وقت مسلمانوں کی کوئی جماعت پہلے سے موجو
نہیں تھی.نئی جماعت تیار کرنی تھی اور اول ان کے دلوں میں ایمان راسخ کرنا تھا اور پھر
انہیں بتدریج عملاً مسلمان بنانا مقصود تھا.اس لئے ایک نئی جماعت کے بنانے اور اس کی
تدریجی تربیت کے لئے جس ترتیب کی ضرورت تھی اس ترتیب میں قرآن کریم نازل ہوا.چنانچہ جن آیات اور سورتوں کا تعلق ایمان اور نشانات اور پیشگوئیوں کے ساتھ ہے وہ پہلے
نازل ہوئیں اور جن کا تعلق تفصیلی احکام کے ساتھ ہے وہ بعد میں نازل ہوئیں.لیکن جب
جماعت قائم ہو چکی اور ان کے ایمان راسخ ہو گئے اور پھر ان کی نسل جاری ہوگئی تو پھر ایک
دوسری حالت پیدا ہو گئی.اور اس حالت میں مسلمانوں کی تربیت سے تعلق رکھنے والے
احکام کا حصہ پہلے کر دیا گیا اور ایمان کی تائید میں دلائل اور پیشگوئیوں کا حصہ بعد میں.یہ تو
قرآن کریم کی ظاہری ترتیب کی صورت ہے.معنوی ترتیب کی دریافت کے لئے تدبر کی
ضرورت ہے اور اس کی ایسی ہی مثال ہے کہ اگر ہم ریل گاڑی میں سفر کر رہے ہوں اور محض
سرسری نظر سے کبھی کبھی اردگرد کے نظارہ کو دیکھ لیں تو ہمیں کسی قسم کی کوئی ترتیب نظر نہیں آتی.لیکن اگر ہم ملک کا جغرافیہ جانتے ہوں اور ہمیں زمین کے نشیب وفراز اور دیگر خصوصیات
کے مطالعہ کے ساتھ کسی قدر دلچسپی ہو تو ہمیں ترتیب بھی نظر آجاتی ہے اور ہم اس ترتیب کے
مطالعہ سے اپنے علم میں بھی اضافہ کر سکتے ہیں اور اس سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں.اور یہ اعتراض بھی کہ ایک ہی جگہ ترتیب وار ہر مسئلہ کے متعلق احکام اور ان کے
تائیدی دلائل جمع کیوں نہیں کر دیئے ، قلت تدبر کا نتیجہ ہے.میں بیان کر چکا ہوں کہ
قرآن کریم مجموعہ ہے کامل ہدایت کا اور اس میں ہر زمانہ کے حالات کے مطابق تعلیم اور
ہدایت رکھ دی گئی ہے.اسی طور پر جیسے زمین اور باقی کائنات میں انسان کی ہر قسم کی ترقی کے
سامان رکھ دیئے گئے ہیں.قرآن کریم محض دلائل کا مجموعہ یا فہرست نہیں ہے بلکہ ایک زندہ
کلام ہے جس کے تازہ بتازہ جو ہر ہر زمانہ میں کھلتے رہتے ہیں.اول تو اس کے سمجھنے کے لئے
پاکیزگی قلب اور عمل شرط ہے اور پھر تدبر اور تفقہ ضروری ہے کہ اس سے انسان کی دماغی اور
54
Page 55
ذہنی ترقی ہوتی ہے.اور پھر قرآن کریم کی یہ ایک صفت ہے کہ اس کی مختصر عبارتوں میں
ہزاروں لاکھوں بلکہ کروڑوں مطالب مرکوز ہیں جن کا مجموعی طور پر شمار ناممکن ہے.جیسے خود
قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر تمام سمندر سیاہی بن جائیں اور ایسے ہی سات
سمندر اور سیاہی کے ہوں اور تمام درخت قلمیں بنالی جائیں تو یہ سیاہی اور قلمیں لکھتے لکھتے ختم
ہو جائیں گی لیکن اللہ تعالیٰ کے کلمات ختم نہ ہوں گے.اس سے قرآن کریم کے وسیع مطالب
کا اندازہ ہوسکتا ہے اور یہ مطالب ایک آیت کو دوسری آیت پر پیش کرنے اور ان کو آپس میں
ملانے اور ان کا ربط دریافت کرنے وغیرہ سے حاصل ہوتے ہیں.اب جو ظاہری ترتیب
قرآن کریم کی ہے بعض مطالب تو اسی ترتیب سے معلوم ہو جاتے ہیں لیکن مبصرین اور
ماہرین زیر غور مسائل سے متعلق مختلف مقامات کے ربط کے مطابق ان مسائل کا حل معلوم
کرتے ہیں اور وہ ترتیب فوراً ان کی مبصرانہ اور ماہرانہ نگاہ کے سامنے آجاتی ہے.اس کی
مثال ایسی ہی ہے کہ آپ کا لکا سے شملہ کے سفر کے لئے روانہ ہوں تو ایک ترتیب، سلسلہ کوہ کی
تو آپ کو سامنے نظر آتی ہی ہے کہ پہلے چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں اور ان کے درمیان مختلف
قسم کی کھیتی یا فصل ہے اور درخت اور جھاڑیاں بوٹیاں بھی مختلف قسم کی ہیں.پھر جوں جوں
آپ بلندی پر جاتے ہیں تو پھولوں، جھاڑیوں اور درختوں کے اقسام بھی بدل جاتے ہیں اور
بعض قسم کے فصل غائب ہو جاتے ہیں اور صرف چند خاص قسم کے رہ جاتے ہیں.اور پھر اور
بلندی پر پہنچ کر اور بھی تغیر ہو جاتا ہے اور ہوا زیادہ ہلکی اور ٹھنڈی ہو نے لگتی ہے اور دور کی
پہاڑیوں پر برف نظر آنے لگتی ہے.اب یہ ایک ترتیب ہے جو ایک عام مسافر کو نظر آتی ہے
لیکن ایک علم نباتات کے ماہر کو ایک اس سے گہری ترتیب نظر آتی ہے.وہ جب مختلف قسم کے
پھولوں اور جھاڑیوں اور پتوں اور درختوں کو دیکھتا ہے تو وہ اپنے علم کی بناء پر کئی قسم کی
ترتیبیں ان میں پاتا ہے اور پھر اپنے دل میں موازنہ کرتا ہے کہ یہ حصہ تو فلاں قسم کا طبقہ ہے
اور ملک کے دیگر طبقات کے ساتھ فلاں قسم کی تقسیم میں آتا ہے اور اس کے اندر ضرور یہ خواص
ہونگے اور یہ فلاں فلاں غرض کے لئے مفید ہو سکتا ہے.اور اسی طرح اپنے ذہن میں وہ
55
Page 56
مختلف طبقات کا موازنہ کرتا چلا جاتا ہے.اس کی نظروں اور ذہن کے سامنے ایک ایسا دفتر
کھلا ہو اہوتا ہے جس سے اس کے پاس بیٹھا ہوا ایک عام مسافر بالکل بے خبر ہوتا ہے.اور یہ
ماہر شخص ہر قدم پر نیا حسن دیکھتا ہے اور نئی خوبیاں اس کے آنکھوں کے سامنے کھلتی ہیں اور نیا علم
اس کو حاصل ہوتا ہے اور اس طرح اگر ایک مسافر طبقات الارض کا ماہر ہو تو وہ پتھروں اور
چٹانوں کی ساخت اور رنگ اور ترتیب کو دیکھ کر ان سے نتائج اخذ کرتا ہے.وہ عام مسافر اور
علم نباتات کے ماہر سے الگ ایک اور ہی دنیا کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس دنیا کا زمین کے
دوسرے حصوں اور دوسرے طبقات کے ساتھ اپنے ذہن میں مقابلہ کر رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے
کہ یہ طبقہ تو فلاں طبقہ سے مشابہ ہے جو یہاں سے پانچ سو میل کے فاصلہ پر ہے یا پانچ ہزار
میل کے فاصلہ پر ہے.اور اس کے یہ خواص ہیں اور یہ خصوصیات ہیں.اور اس سے یہ فائدہ
اٹھایا جاسکتا ہے.اور اس کو یوں کام میں لایا جاسکتا ہے اور جوں جوں وہ آگے بڑھتا ہے نئے
نئے نظارے اس کے سامنے آتے ہیں.اور وہ ان میں محو ہو کر اپنے سفر کو کاٹتا چلا جاتا ہے.یہ
متینوں شملہ پہنچنے تک اپنی اپنی استعداد اور علم اور تدبر کے مطابق گو یا الگ الگ ملکوں سے گذر
ے ہوتے ہیں حالانکہ انہوں نے اکٹھے سفر کیا ہے.لیکن ایک کی آنکھوں نے کچھ دیکھا اور
دوسرے کی آنکھوں نے کچھ اور دیکھا اور تیسرے کی آنکھوں نے کچھ اور.اور ان کے ذہنوں
اور دماغوں نے مختلف نتائج اخذ کئے اور ان کے علوم میں مختلف طور کا اضافہ ہوا.اور یہ تو ایک
سرسری سفر کا نتیجہ تھا.اگر یہ دونوں ماہرین فراغت سے مطالعہ کریں تو اپنے اپنے رنگ میں
انواع و اقسام کے نتائج اخذ کر سکتے ہیں اور اپنے اور دوسروں کے علوم میں بہت سا اضافہ
کر سکتے ہیں.اور پھر جو کچھ وہ یہاں سے حاصل کریں اس کا وہ دیگر مقامات سے مقابلہ اور
موازنہ کریں گے اور اپنے یہاں سے حاصل کردہ علم کو اپنے اور دوسرے ماہرین کے پہلے
سے حاصل کردہ علم پر پیش کریں گے اور اس سے کئی قسم کے مفید اصول اور نتائج نکالیں گے.مثلاً طبقات الارض کے بعض ماہرین معدنیات یا تیل کی تلاش میں پھرتے رہتے ہیں اور وہ
پتھروں اور چٹانوں یا ریت کے ذروں یا مٹی کو دیکھ کر ہی اندازہ کر لیتے ہیں کہ اس مقام پر
56
Page 57
فلاں قسم کی دھات یا تیل یا گیس مل سکتی ہے.اور بعض دفعہ اس قسم کی چٹانیں یار بیت وغیرہ کئی
سو یا کئی ہزار میل کے فاصلہ پر ہوتی ہیں اور ماہرین کا اندازہ یہ ہوتا ہے کہ زمین کے نیچے ہی
نیچے ان کا آپس میں تعلق ہے اور ایک لمبا سلسلہ ایسی چٹانوں یاریت یا مٹی کا چلا گیا ہے جسے
ہم ظاہری آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے.ایک غیر محد و دخترانه
تو یہی حال اللہ تعالیٰ کے کلام کا ہے.اس کے مطالب اور ان کے انواع کا شمار اور حد
نہیں.اور وہ محض ایک کتاب نہیں بلکہ ایک زندہ عالم ہے جس کے خزانے ہمیشہ کھلتے رہیں
گے.ایک بے پر وانظر سے دیکھنے والے کی نگاہ میں اس کے اندر کوئی ترتیب نہیں.ایک عام
تدبر کرنیوالے کی نگاہ میں اس کے اندر ایک ترتیب ہے.ایک گہرے تدبر کرنیوالے کی نگاہ
میں اس کے اندر ایک اور ترتیب ہے اور مبصرین اور ماہرین کی نگاہوں میں تو اس کے اندر
کئی جہان بس رہے ہیں.اور ہر لحظہ نئے علوم اور نئے خزانوں کا انکشاف ہو رہا ہے.اور جوں
جوں یہ انکشاف ہوتا ہے اس کے مطالب میں کسی قسم کی کمی نہیں آتی بلکہ آگے اور وسیع در وسیع
مطالب نظر آنے لگتے ہیں اور یہ ماہرین محسوس کرنے لگ جاتے ہیں کہ بے شک اگر تمام
سمندر سیاہی بن جائیں اور پھر سات اور سمندروں کا ان میں اضافہ ہو جائے اور تمام درختوں
کی قلمیں بنائی جائیں تو یہ سیاہی اور قلمیں لکھتے لکھتے ختم ہو جائیں گی لیکن اللہ تعالیٰ کے کلمات
ختم نہ ہونگے.یہ مثال جو میں نے دی ہے اس لئے بھی موزوں ہے کہ کائنات اللہ تعالیٰ کا فعل ہے
اور قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا قول ہے.اور اللہ تعالیٰ کے فعل اور اس کے قول میں نہ صرف مقابلہ
یا اختلاف نہیں بلکہ ان کا آپس میں گہرا جوڑ اور رشتہ ہے، اور ہونا چاہئے.اور اسی لئے بار بار
قرآن کریم میں زمین اور آسمان اور چاند اور سورج اور ان کی پیدائش اور ان کے فرائض اور
57
Page 58
خواص اور ان کے پیدا کرنے کی غرض کی طرف توجہ دلائی گئی ہے اور ان کے مطالعہ پر زور دیا
گیا ہے اور بارہا ان کو بطور شواہد اور دلائل کے پیش کیا گیا ہے چنانچہ ایک مقام پر فرمایا ہے:
إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ.الَّذِيْنَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيمًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِي خَلْقِ
السَّمواتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.یعنی آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے اختلاف میں بہت سے نشانات
ہیں صاحب دانش لوگوں کے لئے جو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہوئے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے
ہیں اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش پر غور کرتے ہیں اور پھر ان نشانات کو دیکھ کر جو اللہ تعالیٰ
نے ان میں رکھے ہیں وہ چلا اٹھتے ہیں کہ اے ہمارے ربّ! بے شک تو نے یہ ساری
کائنات بے مطلب اور بے مقصد پیدا نہیں کی اور ایسا کرنا تو تیری شان سے بھی بعید تھا.سو
ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم ان سے پورا پورا فائدہ اٹھا سکیں اور پورے طور پر تیری مرضی کو پورا
کرسکیں.ایسا نہ ہو کہ ہم غفلت میں پڑ جائیں اور آخر میں ہمارا حصہ حسرت اور افسوس اور
سوزش قلب ہی رہ جائے.اسی طرح پہلی قوموں کی تاریخ کو بھی اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن کریم میں بطور مثال
اور دلیل کے پیش کیا ہے اور اس کے مطالعہ کی طرف توجہ دلائی ہے اور ان مثالوں اور دلائل
اور شواہد کے پیش کرنے سے یہ غرض بھی ہے کہ انسان کو علوم کے حصول کی طرف توجہ ہو جس
کے نتیجہ میں اس کی معرفت میں ترقی ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں ترقی کر سکے.أسوة رسول الله
قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک کامل ہدایت نامہ عطا فر مایا ہے اور رسول اللہ
سورة آل عمران - آیات 192-191
58
Page 59
صلى الله
کے وجود میں اس نے ہمیں ایک کامل ہادی اور راہ نما عطا فرمایا ہے.جیسے قرآن کریم
میں فرمایا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُوْلِ اللهِ أسْوَةٌ حَسَنَةٌ یعنی تمہارے لئے
اللہ تعالیٰ کے رسول کی ذات میں کامل نمونہ موجود ہے اور پھر فرمایا قُلْ إِنْ كُنتُمْ تُحِبُّونَ
اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ " یعنی اے رسول مومنین سے کہدے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ
سے محبت کرتے ہو تو تمہاری قدرتی خواہش ہونی چاہئے کہ وہ تم سے محبت کرے.اور اگر
تمہاری خواہش ہے تو میری اتباع کرو پھر اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا.اور پھر فرمایا: قُلْ إِنَّ
صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ.لَا شَرِيكَ لَهُ
وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ وَ اَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ.یعنی اے رسول مومنوں سے کہدے کہ
میری عبادتیں اور میری قربانیاں اور میری تمام زندگی اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہے جو تمام
کائنات کا رب ہے، جس کا کوئی شریک نہیں.اور یہ چیزیں بھلا میری کس طرح کہلاسکتی ہیں
میں تو کچھ بھی نہیں.اصل تو وہ ہی ہے اور میرایوں اپنے تئیں درمیان سے ہٹا لینا یعنی ” میں
پر موت وارد کر لینا یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کیلئے ہے، مجھے یوں ہی ارشاد ہوا ہے اور میں سب سے
-
بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار ہوں.غرض آنحضرت ﷺ کی تمام زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کی رضا کی خاطر ہی تھی.ایک
دفعہ کسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا کہ رسول اللہ ﷺ کی زندگی کا معمول
کیا تھا.تو جواب دیا کہ آپ کا خلق قرآن کریم ہی تھا.یعنی جو کچھ قرآن کریم کی تعلیم اور
احکام ہیں وہی آپ کی زندگی تھی.گویا آپ قرآن
کریم کی تعلیم کا زندہ نمونہ تھے.اور کیا
ہی اعلیٰ نمونہ تھے اور کیسا کامل نمونہ تھے.دیگر انبیاء بھی اپنے اپنے زمانہ میں اپنی قوموں کے
لئے نمونہ تھے لیکن اول تو ان کی زندگیوں کے حالات پوری طرح ہم تک پہنچے نہیں اور محفوظ
نہیں رہے.اور جو پہنچے ہیں وہ انسانی دست برد سے محفوظ نہیں رہ سکے کیونکہ بعض بعض سے
سورة الاحزاب.آیت 22
سورة الانعام - آيات 164-163
سورة آل عمران - آیت 32
59
Page 60
متعلق تو ایسی روایات رواج پا گئی ہیں کہ اگر وہ درست ہو تیں تو ایسے اشخاص کو مومن شمار کرنا
بھی مشکل ہوتا.چہ جائیکہ انہیں اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے اور نبی اور رسول قبول کیا جاتا.لیکن چونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان کی نبوت کی تصدیق کی ہے اس لئے ہم انہیں
اللہ تعالیٰ کے نبی یقین کرتے ہیں اور ایسی روایات کو وضعی اور افتراء سمجھتے ہیں کیونکہ وہ ایک نبی
کی شان سے بہت بعید ہے.اور دوسرے وہ انبیاء چونکہ کامل شریعت کے حامل یا پیرو نہیں
تھے اس لئے وہ زندگی کے ہر پہلو میں نمونہ دکھا نہیں سکتے تھے اور نہ انہیں اپنی زندگیوں میں
ایسا نمونہ بنے کا موقعہ ملا.مثلا مسیح علیہ السلام کو لے لو.آپ کی زندگی کے صرف اڑھائی سال
کے حالات ہم تک پہنچے ہیں اور باقی سے متعلق ہمیں علم نہیں اور یہ حالات بھی نامکمل ہیں.اور بعض ایسی روایات ان میں درج ہیں جو ایک نبی کے شایان شان نہیں ہوسکتیں.مثلاً ان کا
ایک شادی کے موقعہ پر پانی کو شراب سے بدل دینا.یا مریم مگدینی کا اپنے سر کے بالوں کے
ساتھ آپ کے پاؤں کی مالش کرنا.یا آپ کا اپنی والدہ کو ” اے عورت“ کے الفاظ سے
خطاب کرنا.یا انجیر کے درخت کو آپ کا لعنت کرنا کیونکہ اس پر بے موسم کا پھل نہ تھا وغیرہ
وغیرہ.لیکن ایسی باتوں کو نظر انداز کر کے بھی ہمیں آپ کی زندگی کے حالات سے صرف یہ
حاصل ہوتا ہے کہ آپ صبر اور حلم اور فروتنی اور بردباری اور دشمنوں کو معاف کر دینے کی تعلیم دیا
کرتے تھے.مگر آپ کی زندگی میں ہمیں ان محدود اخلاق کے اظہار کے مواقع بھی نظر نہیں
آتے.آپ کے دشمن آپ کی زندگی میں جہاں تک انجیل سے ہمیں پتہ چلتا ہے آپ پر
غالب رہے اور آپ کو ان پر بھی غلبہ نصیب نہ ہو ا تا کہ ہم دشمنوں کی معافی کا نظارہ دیکھتے اور
اپنے لئے اسے نمونہ تصور کرتے.نہ آپ کی زندگی میں ہمیں اس
قسم کا نمونہ نظر آتا ہے کہ
انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہئے اور اپنی بیوی اور اولاد کے ساتھ کیسا
اور اپنے دیگر رشتہ داروں کے ساتھ کیسا اور ایک ملازم کو اپنے آقا کے ساتھ کیسا سلوک کرنا
چاہئے اور ایک آقا کو اپنے ملازم کے ساتھ اور بادشاہ کو رعایا کے ساتھ کیسا سلوک کرنا
چاہئے.اور رعایا کو حکومت کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا چاہئے.اور ایک سپاہی میں کن صفات کا
60
Page 61
ہونا لازم ہے اور ایک جرنیل میں کن صفات کا.اور یہ کہ جنگ کے کیا اصول ہونے
چاہئیں اور ایک فاتح جرنیل کو شکست خوردہ دشمنوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہئے.اور تنگی
میں انسان کو کیسے بسر کرنی چاہیئے اور فراخی میں کیسے.اور تجارت کے کیا اصول ہونے چاہئیں
اور ایک تاجر کو کیسا نمونہ دکھانا چاہئے.غرض حضرت مسیح ناصری کی زندگی میں ہمیں یہ بات نظر
نہیں آتی کہ انسانی زندگی کے مختلف شعبوں میں انسان کو کیسا نمونہ قائم کرنا چاہئے.صلى الله
آنحضرت ان کے کامل اخلاق
اس کے مقابل میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت نے چونکہ رسول اللہ علی کو
ایک کامل نمونہ کے طور پر منتخب کیا تھا.اس لئے آپ " کو تمام حالتوں میں سے گذرنا پڑا جن کا
میں نے ذکر کیا ہے تا کہ آپ کی زندگی ہر شعبہ میں بنی نوع انسان کے لئے کامل نمونہ ہو.گو آپ کے والد آپ کی پیدائش سے قبل فوت ہو گئے تھے اور والدہ ابھی آپ چند
ہی سال کے ہوئے تھے تو فوت ہوگئی تھیں.لیکن آپ کے دادا عبدالمطلب اور بعد میں آپ
کے چا ابو طالب نے آپ کو اپنے بچوں کی طرح پالا.اور آپ نے ان دونوں کی اطاعت
اس طور پر کی جیسے ایک بیٹے کو اپنے باپ کی کرنی چاہئے.اور جوانی میں خصوصیت سے آپ
نے اپنے چچا کی اطاعت واعانت کا ایک نہایت ہی اعلیٰ اور قابل تقلید نمونہ قائم کیا حالانکہ
آپ کے چچا اپنی وفات تک مسلمان نہ ہوئے تھے.اور جب آپ کے چچا ضعیف ہو گئے تو
آپ نے ان کے ایک بیٹے حضرت علی کی پرورش اور تربیت اپنے ذمہ لے لی.تا کہ آپ کے
چا کی ذمہ داری ہلکی ہو جائے اور ان کے سر سے بوجھ کم ہو.اور آپ نے نہایت شفقت سے
حضرت علی کی تربیت کی اور بعد میں اپنی بیٹی حضرت فاطمہ ان کے نکاح میں دے دی.اور کئی
سال بعد جب آپ کی بچی مدینہ میں فوت ہوئیں تو آپ ان کے دفن کے وقت خود قبر میں
اترے اور لحد کو صاف کیا.اور اپنی بچی کی نعش کو لحد میں رکھا.اور اس وقت آپ آبدیدہ
61
Page 62
تھے.اور آپ نے فرمایا: ” تو میرے لئے بہت ہی اچھی اور شفیق ماں تھی.“ اور اس بات کا
اندازہ کہ آپ ماں کا درجہ کیا سمجھتے تھے، آپ کے اس قول سے ہوسکتا ہے کہ جنت ماں کے
پاؤں کے نیچے ہے.اور آپ بار بار ماں باپ کی اطاعت کی تلقین فرمایا کرتے تھے.اور ایک
شخص کے نہایت اعلیٰ اور پسندیدہ عمل کا یوں ذکر فرماتے تھے کہ وہ اپنے بوڑھے ماں باپ کو ہر
شام دودھ پلایا کرتا تھا.ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ اسے دودھ لانے میں دیر ہوگئی اور اس کے
ماں باپ سو گئے.لیکن وہ دودھ لئے ان کے سرہانے کھڑا رہا اور تمام رات ایسے ہی گذار
دی.صبح کے وقت جب اس کے ماں باپ بیدار ہوئے تو اس نے دودھ انہیں پینے کو دیا.اس
نے یہ تمام تکلیف برداشت کی لیکن یہ پسند نہ کیا کہ ماں باپ کی نیند میں خلل ڈالے یا ان کے
دودھ پینے میں ناغہ ہو ( یہ ایک لمبی حدیث کا ایک حصہ ہے ).آپ اپنی انا حلیمہ کی بھی بہت عزت اور اپنے رضاعی بہن بھائیوں سے بہت محبت
کیا کرتے تھے.بلکہ حلیمہ کے تمام قبیلہ والوں کے ساتھ آپ حسن سلوک سے پیش آتے
تھے.نبوت کا درجہ عطا ہونے سے پہلے بھی آپ کی زندگی ہر رنگ میں نمونہ تھی.آپ کی
عفت اور حیا اور امانت اور محتاجوں کی خبر گیری اور مہمان نوازی اور سخاوت مسلّمہ تھی.اور
جوانی میں ہی آپ اپنے اہل وطن میں الامین کے نام سے مشہور تھے.بیوی سے سلوک
حضرت خدیجہ مکہ کی ایک متمول ہیوہ تھیں.آپ نے رسول اللہ ﷺ کو نبوت کے
زمانہ سے بہت پہلے اپنی طرف سے تجارت کا مال و اسباب دیگر شام کی طرف تجارت کے
لئے بھیجا اور آپ کی دیانت و امانت اور دانش کا خدیجہ پر اس قدر اثر ہوا کہ خدیجہ نے آپ
کو پیغام نکاح بھیج دیا جسے آپ نے منظور کر لیا.اس وقت حضرت خدیجہ کی عمر چالیس سال تھی
62
Page 63
اور آپ
کی عمر پچیس سال تھی.حضرت خدیجہ نے نکاح کے بعد اپنا تمام مال اور اپنے تمام غلام
آپ کے حوالہ کر دیئے.آپ نے وہ مال محتاجوں میں تقسیم کر دیا اور غلاموں کو آزاد کر دیا.حضرت خدیجہ آپ کے عقد میں آنے کے بعد کم و بیش پچیس سال زندہ رہیں اور جس وقت
الله
وہ فوت ہوئیں حضور ﷺ کی عمر پچاس سال کے قریب تھی.ان کے بطن سے حضور کے تین
صاحبزادے اور چار صاحبزادیاں ہوئیں اور حضور ﷺ نے دنیا کے سامنے خاوند اور باپ
کی حیثیت میں کامل نمونہ قائم کیا.اور یوں آپ نے اپنے اقوال سے بھی عورتوں کے ساتھ
حسن معاشرت کی تعلیم دی.اور فرمایا: خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِاهْلِهِ تم میں سب سے بہتر وہ
ہے جو اپنے گھر کے لوگوں کے ساتھ بہتر سلوک کرے.حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول
الله عله حضرت خدیجہ کا ہمیشہ اس رنگ میں ذکر فرمایا کرتے تھے کہ میں آپ کی زندہ
بیویوں میں سے کسی کا اتنا رشک نہیں کرتی تھی جتنا فوت شدہ خدیجہ کا.اور اگر حضرت
خدیجہ کی سہیلیوں میں سے کوئی حضور کو ملنے آجاتی تھی تو آپ خاموشی سے اٹھ کھڑے
ہوتے تھے اور اپنا کپڑا اس کے بیٹھنے کے لئے بچھا دیا کرتے تھے.اور جب کوئی تحفہ وغیرہ آتا
تھا تو اسے تقسیم فرماتے ہوئے حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو بھی حصہ بھیجا کرتے تھے.بچوں پر شفقت
سب بچوں کے ساتھ حضور ﷺ بہت شفقت سے پیش آیا کرتے تھے.ایک دفعہ
حضور اپنے نواسوں کے ساتھ پیار کر رہے تھے تو ایک بدوی نے کہا یا رسول
اللہ ﷺ آپ
اپنے بچوں کو چوم بھی لیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں.اس نے کہا میرے تو اتنے بچے ہیں،
میں نے تو آج تک ان میں سے کسی کو نہیں چوما.تو آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارا
دل سخت کر دیا تو میں اس کا کیا علاج کروں ؟.کئی دفعہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو امام حسن یا امام حسین سجدہ کے وقت
63
Page 64
شفقت ا.آپ کے کندھوں پر سوار ہو جاتے تھے لیکن آپ اسے برانہیں مناتے تھے.لیکن یہ
پنے دائرہ کے اندرتھی.تمام دنیا جانتی ہے کہ آپ کو اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کس
قدر محبوب تھیں لیکن آپ ان سے بھی فرمایا کرتے تھے کہ اے فاطمہ عمل کیجیو، عمل
كيجيو کیونکہ آخرت میں تجھ سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ تو کس کی بیٹی ہے بلکہ یہ سوال ہوگا
کہ تو عمل کیا کرتی رہی ہے.ایک دفعہ آپ گھر تشریف لائے تو حضرت عائشہؓ نے عرض کیا کہ فاطمہ آئی تھی اور
آپ سے کچھ کہنا چاہتی تھی.میں نے ٹھہرانا چاہا لیکن وہ واپس اپنے مکان پر چلی گئی.چنانچہ
آپ حضرت فاطمہ کے مکان پر تشریف لے گئے اور دریافت کیا کہ کیا بات تھی.بیٹی نے
عرض کیا کہ پتھر سے اناج کوٹتے کوٹتے میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے ہیں.میں یہ
عرض کرنے کے لئے گئی تھی کہ آئندہ جب غلام تقسیم ہوں تو کوئی لونڈی یا غلام مجھے بھی عطا ہوتا
میں اس تکلیف سے بچ جاؤں.محبوب خدا کی بیٹی ، خاتم الانبیاء کی نور چشم ، شاہ عرب کی
لخت جگر ، گھر میں ایک لونڈی غلام نہیں.دو جہانوں کے سرتاج باپ سے عرض کرتی ہے کہ اگر
غلام یا لونڈی عطا ہو تو اس مشقت سے نجات پاؤں جس سے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے
ہیں.حضور ﷺ نے جواب دیا فاطمہ کیا میں تجھے وہ بات نہ بتاؤں جو تیرے لئے دنیا اور
آخرت میں کئی لونڈیوں اور غلاموں سے بہتر ہے؟ بیٹی نے عرض کیا فرمائیے.آپ نے فرمایا
سوتے وقت ۳۳ دفعہ سبحان اللہ اور ۳۳ دفعہ الحمد لله اور ۳۴ دفعہ اللہ
ڑھا کرو.یعنی خدا کی تسبیح وتحمید و تکبیر میں مشغول رہو.بیٹی نے عرض کیا میں ایسا ہی کروں
گی اور لونڈی غلاموں کی خواہش دل سے نکال دی.ایک دفعہ آپ صدقہ کی کھجور میں تقسیم فرمارہے تھے.امام حسن یا امام حسین کھیلتے کھیلتے
آ نکلے اور کھجوروں کے ڈھیر سے ایک کھجور اٹھا کر منہ میں ڈال لی.آپ نے اپنی انگلی نوا سے
کے منہ میں ڈال کر کھجور نکال کر باہر پھینک دی اور فرمایا : آل محمد ﷺ کے لئے صدقہ کھانا
جائز نہیں.الله
اکبر
64
Page 65
ایک دفعہ قریش کے ایک معزز خاندان کی ایک عورت پر سرقہ کا الزام ثابت ہوا.قضاء کا حکم جاری ہوا، اس کا ہاتھ کاٹ ڈالا جائے.قریش کے معززین نے اسامہ بن زید کے
واسطے سے حضور ﷺ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ معزز خاندان کی عورت ہے اس کی سزا
میں حضور ع تخفیف فرما ئیں یا معاف کر دیں.حضور نے فرمایا وَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ
لَوْسَرِقَتْ فَاطِمَةُ لَقَطَعْتُ يَدَهَا.یعنی مجھے اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان
ہے اگر میری بیٹی فاطمہ بھی سرقہ کرے تو میں اس کا ہاتھ کٹوا دوں.آپ کا لخت ابراہیم فوت ہو گیا.اولا د ہونے کے لحاظ سے بھی عزیز اور بڑھاپے کا
اس وقت اکلوتا ہی بیٹا.باپ نے اپنے محبوب کی رضا کو صبر اور شکر کے ساتھ قبول کیا اور فرمایا
الْعَيْنُ تَدْمَعُ وَ الْقَلْبُ يَحْزُنُ وَلَا نَقُوْلُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا وَ إِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا
إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ.یعنی آنکھ بہتی ہے اور دل بے شک مغموم ہے لیکن ہم وہی کہتے ہیں
جو ہمارے رب
کو پسند ہو اور منہ سے ایسا کلمہ نہیں نکالتے جو اسے ناپسند ہو.گواے ابراہیم
ہمیں تیری جدائی کا غم ہے.یہ ذکر آچکا ہے کہ جب آپ حضرت خدیجہ کی طرف سے بطورا ایجنٹ یا ملازم تجارت پر
بھیجے گئے تھے تو آپ نے اپنے فرائض کو کس خوبی اور خوش اسلوبی کے ساتھ ادا کیا.غلاموں سے سلوک
آپ ﷺ خود تو غلام رکھتے ہی نہیں تھے.مدینہ میں بھی جب
کبھی کوئی غلام آپ
کے حصہ میں آتا تھا تو آپ اس کو آزاد کر دیتے تھے.مکہ میں شروع شروع میں آپ کے پاس
زید نامی ایک غلام تھا.یہ ایک معزز عرب خاندان کا نوجوان تھا.کسی جنگ میں قید ہو کر غلامی
میں بک گیا تھا اور ہوتے ہوتے رسول اللہ علیہ کی ملکیت میں آ گیا.یہ شروع نبوت کا
زمانہ تھا جب اس کے والد اور چا کو علم ہوا کہ یہ مکہ میں ہے تو رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں
65
Page 66
حاضر ہوئے تا زید کو واپس خرید کر ساتھ لے جائیں.رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ زید کو
اختیار ہے جہاں چاہے جائے.لیکن زید نے آپ سے جدا ہونے سے انکار کر دیا.اس کے
باپ نے حیرانی کا اظہار کیا اور زید سے کہا کہ تو غلامی کو آزادی پر ترجیح دیتا ہے؟ زید نے کہا
ان کی غلامی مجھے ہزار آزادیوں سے بہتر ہے.چنانچہ اس کے عزیز مایوس واپس چلے گئے.لیکن رسول اللہ ﷺ نے فوراً اسے کعبہ میں لے جا کر آزاد کر دیا.حضرت انس کئی سال رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں بطور ملا زم کے رہے اور وہ
روایت کرتے ہیں کہ مجھے اس تمام عرصہ میں رسول اللہ ﷺ نے کبھی اُف تک نہیں کہی.22 مئی
آپ ﷺ ہمیشہ غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید فرماتے تھے.آپ کا ارشاد
تھا کہ جیسا کپڑا آقا پہنے ویسا ہی غلام کو پہننے کے لئے دے اور جیسا کھانا خود کھائے ویسا ہی
غلام کو کھانے کے لئے دے.اور اگر اسے ایسا کام کرنے کو دے جو مشقت کا کام ہو تو خود بھی
اس کام میں اس کی مدد کرے.اسی تعلیم کا نتیجہ تھا کہ جب حضرت عمر کی خلافت کے زمانہ میں
یروشلم فتح ہوا اور وہاں کے بشپ نے اصرار کیا کہ مسلمانوں کا خلیفہ خود یروشلم آئے تا اس کے
سامنے ہم اطاعت قبول کریں.اور حضرت عمرؓ نے بیت المقدس کا سفر اختیار کیا اور آپ کے
ساتھ ایک غلام تھا اور دونوں کے پاس ایک ہی اونٹنی تھی.تو آپ نے اصرار کیا کہ ایک منزل
غلام سوار ہو اور ایک منزل آپ سوار ہوں.اور جب یروشلم کے قریب پہنچے تو غلام کے سوار
ہونے کی باری تھی.اور غلام اونٹ پر سوار تھا اور عمر بن خطاب خلیفتہ الرسول، امیر المؤمنین،
شاہ عرب اس
اونٹنی کی رسی پکڑے ہوئے پیدل چلے آرہے تھے.،
آنحضرت ﷺ غلاموں کو آزاد کرنے کی بھی تلقین فرماتے رہتے تھے اور غلام کو
آزاد کرنا اسلام میں بہت ثواب کا کام سمجھا جاتا تھا.ایک دفعہ آپ کہیں سے گذر رہے تھے.66
Page 67
آپ نے دیکھا کہ ایک آقا اپنے کسی غلام کو کوڑے مارنے کو ہے.آپ نے سختی سے اس کو
پکارا کہ کیا کرتے ہو.وہ آپ کی آواز سن کر چونک پڑا.اور اس نے فوراً کہا یا رسول اللہ ! میں
نے اسے آزاد کیا.آپ نے فرمایا اگر تو ایسانہ کرتا تو جہنم کی آگ تیرے چہرے کو چھوتی.اور یہ بھی یا درکھنا چاہئے کہ اسلام میں صرف ایک صورت ہی غلام بنانے کی ہے اور وہ
یہ کہ اگر کوئی قوم جبر سے لوگوں کو اسلام لانے سے روکتی ہو یا اسلام ترک کرنے پر مجبور کرتی ہو
اور آزادی ضمیر کے لئے اس کے ساتھ جنگ کی جائے اور اس جنگ میں اس قوم کے لوگ قید
ہو کر آئیں اور پھر اس قوم کے لوگ نہ اس کا مبادلہ کر سکیں اور نہ فدیہ ادا کریں تو وہ قیدی غلام
بنائے جاسکتے ہیں.کیونکہ انہوں نے دوسرے لوگوں کو روحانی غلامی میں ڈالنا چاہا تھا.اس
لئے ان کی سزا یہ مقرر ہوئی کہ انہیں جسمانی غلامی میں ڈالا جائے لیکن بار ہا ایسا ہوا کہ ایسے
غلام مسلمانوں میں رہ کر اسلام لے آئے اور وہی نور جسے وہ لوگوں سے روکتے تھے ان کے
دلوں اور جانوں کو منور کرنے لگا اور ان کی ابدی آزادی کا باعث بن گیا.اور یوں بھی آپ کیقیموں اور بیواؤں اور بے کسوں کی خبر گیری میں مستعد رہتے تھے
اور جہاں دیکھتے تھے کہ کسی غلام سے ایسی مشقت کا کام لیا جاتا ہے جو اس کی طاقت سے باہر
ہے یا اس کے لئے باعث تکلیف ہے تو اس کی مدد فرماتے تھے اور اس کا ہاتھ بٹاتے تھے.گو
یہ آخری قسم کے واقعات حضور کی مکی زندگی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں کیونکہ مدینہ میں تو بوجہ
حاکم ہونے کے آپ نے حکما ایسی باتیں منع فرما دی تھیں.حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حضور کی سیرت کے اس پہلو کو کس خوبی کے ساتھ
بیان فرمایا ہے
خواجه و
مر عاجزان را بنده
پادشاہ و بے کساں را چاکرے
67
Page 68
صلى الله
آنحضرت یہ ایک حاکم کی حیثیت میں
علوس
دعوی نبوت کے بعد آپ کی مکی زندگی میں آپ " کو اور آپ کے اصحاب کو طرح
طرح کے دکھ دیئے گئے.لیکن آپ نے مکہ میں جو بھی نظام حکومت قائم کیا تھا اس کے خلاف
کبھی کوئی منصوبہ نہیں کیا اور نہ کوئی مقابلہ کی راہ اختیار کی.مدینہ پہنچ کر مدینہ کے مسلمان، یہود
اور مشرکین نے آپ کو اپنا حاکم تسلیم کر لیا.اور آہستہ آہستہ مدینہ کے مشرکین تو مسلمان ہو گئے
اور صرف مسلمان اور یہو دمدینہ میں رہ گئے گو بعد میں یہود بوجہ اپنی شرارتوں اور سازشوں اور
غداریوں کے بعض جلا وطن کئے گئے اور بعض کو سزائے موت دی گئی.لیکن جب تک وہ مدینہ
میں رہے رسول اللہ ﷺ کو اور مسلمانوں کو طرح طرح کے فتنوں میں مبتلا کرتے رہے.ادھر قریش مکہ اور عرب کے دیگر مشرک قبائل بار بار مدینہ پر حملہ آور ہوتے تھے یا حملہ کی
تیاریاں کرتے تھے.اور مدینہ میں مسلمانوں کی یہ حالت تھی کہ کوئی دن ان پر چین یا امن کا نہ
گذرتا تھا.ایک صحابی کا قول ہے کہ اس زمانہ میں ہم حسرت سے کہا کرتے تھے کہ یا اللہ ہم پر
کوئی ایسا بھی زمانہ آئے گا کہ ہم رات کو سوئیں گے اور ہمارے دلوں میں سوائے تیرے خوف
کے اور کوئی خوف نہ ہوگا.لیکن باوجود ان تمام مشکلات کے رسول اللہ ﷺ کو شروع سے ہی مدینہ میں
حکومت حاصل تھی اور آہستہ آہستہ اس حکومت کا حلقہ وسیع ہوتا گیا.حتی کہ فتح مکہ کے بعد
آپ تمام جزیرۂ عرب کے بادشاہ تسلیم کر لئے گئے.گویا ہجرت کے بعد کا زمانہ آپ کی
حکومت کا زمانہ تھا اور اس زمانہ میں آپ نے ہمارے لئے ایک کامل جرنیل اور بادشاہ کا نمونہ
قائم کیا.آپ جنگوں میں خود کمان کیا کرتے تھے گو اپنے ہاتھ سے آپ نے کسی کو قتل نہیں کیا.آپ بعض دفعہ جنگ میں زخمی بھی ہوئے اور بعض دفعہ جنگ کی حالت سخت خطرناک اور
تشویشناک ہو جاتی تھی لیکن آپ کی طرف سے کسی وقت بھی کمزوری کا اظہار نہیں ہوا.بے شک آپ نہایت بے قراری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں کرتے رہتے تھے.68
Page 69
کیونکہ آپ کا ایمان پختہ تھا کہ فتح وشکست اصل میں اسی کے ہاتھ میں ہے اور وہ بے نیاز
ہے.جسے چاہتا ہے فتح عطا کرتا ہے.بعض مہموں پر آپ نے فوج کو دوسروں کی کمان کے
ماتحت بھی بھیجا اور ہدایات دیں کہ دشمن کی کھیتیوں اور ثمر دار باغوں کو تباہ نہ کرنا.سایہ دار
درخت نہ کاٹنا ، بچوں ، عورتوں اور بوڑھوں کو دکھ نہ دینا.راہبوں اور پادریوں وغیرہ کو ایذا نہ
پہنچانا.جب دشمن صلح کی طرف مائل ہو تو صلح کی طرف جھک جانا اور محض غنیمت کے طمع یا بدلہ
کی خاطر جنگ کو جاری نہ رکھنا.چونکہ آپ نے عام طور پر یہ حکم بھی دیا تھا کہ کسی شخص کو آگ کا عذاب نہ دیا جائے اس
سے یہ بھی نتیجہ نکلتا ہے کہ دفاع کی صورت میں مجبور ہو کر اگر ایسا کرنا پڑے تو الگ امر ہے
ور نہ اسلام جنگ میں ایسی توپ، بم وغیرہ کے استعمال کی اجازت نہیں دیتا جس کے استعمال
سے آگ کا استعمال لازم آتا ہے.آنحضرت ﷺ کی سادہ زندگی
پھر اس بادشاہ کا دربار کیسا تھا؟ فوجوں کے پہرے، چوبدار کی وردیاں، زرق برق
پوشاکیں ، بینڈ باجے ،محلات، آرائش، فرش و فروش ، جھاڑ فانوس، تصاویر اور بت ، دیوان عام
اور خاص ، آراستہ تخت ، در بار اور جشن ،لونڈیاں اور غلام کچھ بھی نہ تھا.حتی کہ اس شاہ دو عالم کے سونے کے لئے پلنگ بھی نہیں تھا.آپ زمین ہی پر سو
جاتے تھے اور آپ کا بستر ایک چمڑے کا گدا تھا جس میں کھجور کے خشک پتے بھرے ہوئے
تھے اور بسا اوقات آپ کھجور کی شاخوں کی کھردری صف پر ہی لیٹ کر سو جاتے تھے.اور
جب آپ اس پر سو کر اٹھتے تھے تو آپ کے بدن پر ان شاخوں کے نشان ہو ا کرتے تھے.رہنے کو کچے جھونپڑے تھے.ایک کچی مسجد جس کی چھت بھی کھجور کی خشک شاخوں
کی تھی اور
بارش میں پکا کرتی تھی.یہ مسجد بھی تھی اور دار الشوریٰ بھی تھی.یہیں حضور نمازیں پڑھا کرتے
69
Page 70
تھے.یہیں دربار رسالت لگا کرتا تھا.یہیں صحابہ کرام سے ملاقات ہوتی تھی ،مشورے ہوتے
تھے، امور سلطنت سرانجام پاتے تھے.بڑے بڑے بادشاہوں کے ایلچیوں سے بھی یہیں
ملاقات ہوتی تھی.نہ کوئی چپڑاسی نہ چوبدار، نہ وردی نہ کمر بند.حضور کا اپنا لباس نہایت سادہ
ہو ا کرتا تھا اور کسی قسم کے کوئی ضابطے اور پابندیاں نہیں تھیں.اور ساتھ ہی حضور ﷺ کا
رعب اس قدر تھا کہ کسی کو نظر اٹھا کر دیکھنے کی نہ جرات ہوتی تھی نہ تاب.آپ کی غذا بالکل سادہ تھی.جو بھی غریبانہ طور پر میسر آجاتا تھا وہ تناول فرما لیتے.کئی دفعہ خشک کھجوروں کو کوٹ کر انہیں پر گزارا کر لیا جاتا تھا.کئی کئی دن آپ کے گھروں میں
آگ نہیں جلتی تھی کیونکہ کوئی چیز پکانے کی نہیں ہوا کرتی تھی.حضور اپنے ہاتھ سے کپڑوں میں
پیوند لگا لیتے تھے.جوتے کی مرمت کر لیا کرتے تھے.کسی نے حضرت عائشہ سے پوچھا حضور
جب گھر کے اندر ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا گھر کے کام کاج میں
ہماری مدد کرتے ہیں.رات کا بہت سا حصہ آپ " کا عبادت میں گذرتا تھا.نوافل میں آپ
قیام اس قدر لمبا کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں بعض دفعہ متورم ہو جاتے تھے.حضرت عائشہ
نے ایک دفعہ عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کا تو آپ کے ساتھ مغفرت کا وعدہ ہے پھر آپ اس قدر
عبادت کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کیا میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ مدینہ پہنچنے
کے بعد جب مسجد نبوی کی تعمیر شروع ہوئی تو آپ اپنے صحابہ کے ساتھ ملکر مٹی اٹھاتے تھے اور
ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے تھے.جنگ خندق کے موقعہ پر بھی اسی طرح آپ صحابہ
کے ساتھ شامل ہو کر خندق کھودنے میں مصروف رہے اور بھوک کا یہ عالم تھا کہ حضور نے پیٹ
پر پتھر باندھے ہوئے تھے.عرب میں اس زمانہ میں چکی کا رواج نہیں تھا.جب بعد میں
فتوحات کا سلسلہ وسیع ہوا اور ہر قسم کے آرام کے سامان میسر آنے لگے اس وقت باریک پیسا
ہوا آٹا بھی ملنے لگا.اس زمانہ کی حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ میں جب گندم کے آئے
کی روٹی کھانے لگتی ہوں تو وہ میرے حلق میں پھنستی ہے کیونکہ مجھے ایسے موقعہ پر یاد آجاتا ہے
کہ رسول اللہ ﷺ نے کبھی اپنی زندگی میں گندم کی روٹی سیر ہو کر نہیں کھائی تھی اور ہم اس
الله
70
Page 71
زمانہ میں دو پتھروں کے درمیان غلہ کو کوٹ کر روٹی بنالیا کرتے تھے.آپ نے
کبھی مال جمع نہیں کیا ہاں ضرورت کے وقت قرض لے لیتے تھے.لیکن آپ
کا طریق تھا کہ آپ قرض کی ادائیگی کے وقت قرض کی رقم سے کچھ زائد واپس کر دیتے
تھے.آنحضرت کا عفو اور رحم
کا
آپ کی سرشت میں رحم اور عفو کوٹ کوٹ کر بھرا ہو ا تھا.دعویٰ نبوت کے بعد آپ کی
مکی زندگی میں آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں دی گئیں اور زندگی آپ پر مشکل کر دی گئی.آپ کے صحابہ اور صحابیات کو قسم قسم کے دکھ دیئے گئے.بعض کو سخت بے رحمی سے قتل کیا گیا.مثلاً ایک طریق دکھ دینے کا یہ تھا کہ ایک صحابی کی ایک ٹانگ ایک اونٹ کے ساتھ باندھ دی
گئی اور دوسری ٹانگ دوسرے اونٹ کے ساتھ اور پھر اونٹوں کو مخالف سمتوں میں ہانک دیا
گیا اور اس طرح اس صحابی کے بدن کو دوٹکڑوں میں چیر ڈالا گیا.حضرت بلال غلام تھے ان کا
مشرک آقا انہیں جلتی دھوپ میں جلتی ریت اور پتھروں پر لٹا دیتا تھا اور ان کی چھاتی پر دھوپ
سے جلتے ہوئے پتھر رکھ دیتا تھا اور کہتا تھا کہ محمدکا انکار کرو لیکن وہ کمال اطمینان سے اپنے
ایمان کا اعلان کرتے رہتے تھے.چنانچہ آخر عمر تک ان کی پیٹھ اور سینہ پر اس عذاب کے
نشان باقی تھے.پھر جب حضور ﷺ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے تو قریش کی عداوت اور
بغض میں کوئی کمی نہ آئی اور انہوں نے بار بار مدینہ پرحملہ کئے.جنگی مدافعت کیلئے حضور کوئی
بار جنگ کرنی پڑی جس میں مسلمانوں کو بہت سی تکالیف کا سامنا ہوا اور بہت سے مسلمان
شہید ہوئے لیکن آخر جب مکہ فتح ہوا اور آپ کے خونی دشمن عاجز ہو کر آپ کے سامنے پیش
ہوئے تو آپ نے ان سے دریافت فرمایا کہ اب تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے ؟ انہوں
71
Page 72
نے جواب دیا کہ آپ جو بھی سلوک ہمارے ساتھ کریں ہم اس کے سزاوار ہیں.لیکن آپ
کریم بھائی ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ہم سے ایک کریم بھائی کی طرح سلوک
کرینگے.آپ نے فرمایا: لَا تَشْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْم.یعنی جاؤ میں نے معاف کر دیا.آج
تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا.اور سوائے چند افراد کے جن کو خاص خاص جرائم کی سزادی
گئی ، مکہ والوں کو بالکل معاف کر دیا گیا.کیا دنیا ایسے عفو اور رحم کی مثال پیش کر سکتی ہے.؟
آپ ﷺ کی شجاعت
آپ کی ذاتی شجاعت اور جرات اور اللہ تعالیٰ پر ایمان اور توکل حد درجہ کے تھے.آپ کے دشمن بھی کہا کرتے تھے عَشِقَ مُحَمَّدٌ رَبَّه یعنی محمد علی تو اپنے رب پر عاشق
ہوگیا ہے.اور اس میں کیا شک ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے رب کے عاشق تھے اور آپ " کارب
ย
آپ کا عاشق تھا.ہجرت کے موقعہ پر جب آپ مکہ سے نکل کر غار ثور میں ٹھہر ہوئے تھے تو قریش
کا ایک گروہ آپ کا کھوج لگاتے لگاتے غار کے منہ تک پہنچ گیا.حضرت ابوبکر فرماتے ہیں
کہ ان میں سے بعض کے پاؤں غار کے منہ کے ساتھ نظر آتے تھے اور اگر وہ نیچے نگاہ کر کے
غور سے دیکھتے تو ہمیں دیکھ لیتے.اس وقت میں نے رسول اللہ ﷺ کی خاطر گھبراہٹ کا
اظہار کیا تو آپ نے فرمایا لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللهَ مَعَنا گھبراؤ نہیں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ
ہے.کیسا کامل ایمان اور کامل بھروسہ ہے!
ایک جنگ کے موقعہ پر جب مسلمانوں کی حالت بہت کمزور ہوگئی اور چند گنتی کے
صحابہ آپ کے ساتھ رہ گئے اور آپ خود بھی زخمی ہو گئے تو کفار کی طرف سے بعض اکابر صحابہ
کے نام پکارے گئے تا وہ معلوم کریں کہ وہ زندہ ہیں یا مارے گئے.رسول اللہ علیہ نے
سورة التوبة - آيت 40
72
Page 73
اپنے ساتھیوں سے کہا جن میں وہ صحابہ بھی موجود تھے کہ کوئی جواب نہ دو.پھر انہوں نے
رسول اللہ ﷺ کا نام پکارا.پھر بھی رسول اللہ علیہ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا خاموش
رہو اور کوئی جواب نہ دو.کفار نے جواب نہ پا کر یہ قیاس کر لیا کہ یہ سب لوگ مارے گئے
ہیں.اس پر انہوں نے خوشی کا نعرہ بلند کیا اور اپنے ایک بت کا نام لیکر اس کی بڑائی کی اور کہا وہ
غالب آ گیا.اس پر رسول اللہ ﷺ کی غیرت برداشت نہ کر سکی اور آپ نے اپنے ساتھیوں
سے فرمایا کہ تم زور سے نعرہ لگاؤ کہ اللہ ہی سب سے بزرگ اور بڑی شان والا ہے.ایک دفعہ جب لڑائی کا رخ بظاہر مسلمانوں کے خلاف ہو گیا اور آپ کی حفاظت کا بھی
انتظام نہ رہا اور اسلامی لشکر میں ابتری پیدا ہو گئی اور آپ قریباً اکیلے رہ گئے تو آپ اپنے
گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہوئے دشمن کی طرف بڑھے اور بلند آواز سے دشمن کو پکار پکار کر کہنا
شروع کیا
أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ
أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ
یعنی میں یقیناً خدا کا نبی ہوں اور جھوٹا نہیں ہوں.میں ہی عبدالمطلب کا پوتا ہوں.مراد آپ کی یہ تھی کہ بے شک میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے ماتحت لڑائی اور حفاظت کے ظاہری
سامانوں کو استعمال کرتا ہوں لیکن میرا اصل بھروسہ ان سامانوں پر نہیں ہے بلکہ خدا پر ہے اور گو
میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں اور عبدالمطلب کا پوتا ہوں مگر خدا تعالیٰ کا سچا نبی ہوں اور
وہ ضرور میری حفاظت کرے گا.اور مجھے غلبہ عطا فرمائے گا اور تم لوگ خائب و خاسر ہو گے.چنانچہ اللہ نے ایسا ہی کیا اور اس مخصوص لڑائی میں بھی معجزانہ طور پر لڑائی کا رخ بدل کر
مسلمانوں کو فتح عطا کر دی.ایک دفعہ آپ ایک جنگ سے واپس تشریف لا رہے تھے.راستہ میں دن کے وقت
ایک جگہ قیام ہوا.آپ ایک درخت کے نیچے آرام کرنے کے لئے لیٹ گئے اور آپ نے
اپنی تلوار درخت سے لٹکا دی.معلوم ہوتا ہے کہ پہرہ والوں سے کچھ غفلت ہوگئی.ایک دشمن
73
Page 74
وہاں آنکلا.اس نے آپ کی تلوار درخت سے اتار لی اور آپ کو سوتا پا کر آپ پر چڑھ آیا.آپ کی نیند کھل گئی تو اس نے کہا اے
محمد بنتا اس وقت تجھے کون بچا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا
اللہ.یہ سادہ اور بے ساختہ اور پر تو کل جواب سنتے ہی اس شخص پر کچھ ایسا رعب چھا گیا کہ
تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی.آپ نے اس کی سراسیمگی سے فائدہ اٹھا کر جلدی سے یہ تلوار
اپنے قبضہ میں کر لی اور اس سے کہا.اب
تو بتا تجھے کون بچا سکتا ہے؟ اس نے جواب دیا، کوئی
نہیں.آپ ہی رحم کریں.آپ نے اسے معاف کر دیا.اعتدال پسندی
آپ علیہ کی طبیعت تصنع اور تکلف سے بالکل پاک تھی.آپ نے فرمایا کہ بعض
دفعہ نماز پڑھاتے وقت میں چاہتا ہوں کہ نماز کولمبا کروں مگر اس وقت کسی بچے کے رونے کی
آواز میرے کان میں پڑ جاتی ہے اور میں خیال کرتا ہوں کہ اس کی ماں نماز میں شامل ہوگی
اور اسے پریشانی ہوگی تو میں نماز کو مختصر کر دیتا ہوں.کسی جھوٹے مدعی نبوت کے منہ سے ایسی
صاف اور سچی بات کبھی نہیں نکل سکتی.ایک دفعہ آپ کے پاس شکایت پہنچی کہ فلاں مسجد میں امام عشاء کی نماز بھی کردیتا
ہے.اس وقت آپ نے بہت رنج کا اظہار کیا اور فرمایا : جو شخص ایسا کرتا ہے وہ لوگوں کے
دلوں میں دین سے بیزاری پیدا کرتا ہے.امام کو چاہئے کہ اس بات کا خیال رکھے کہ اس کے
یچھے بچے اور بوڑھے بھی نماز پڑھ رہے ہیں اور ایسے لوگ بھی جو دن بھر کام کر کے
تھکے ماندے ہو رہے ہیں، ان کا خیال رکھنا چاہئے.آپ کی ہدایت تھی کہ باجماعت نماز
لمبی نہ کی جائے.ہاں اپنے طور پر لوگ جس قدر لمبی عبادت چاہیں کریں.چنانچہ میں ذکر چکا
ہوں کہ آپ خود نوافل میں اس قدر لمبا قیام فرمایا کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں بعض دفعہ
متورم ہو جایا کرتے تھے.اور آپ رات کا اکثر حصہ نوافل میں گزار دیتے تھے.74
Page 75
ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص اپنے دوست کے ہاں مہمان گیا.ابھی پردہ کا حکم جاری نہیں ہوا تھا.دیکھا کہ دوست کی بیوی بالکل میلے کچیلے کپڑے پہنے
ہوئے ہے.بال بکھرے ہوئے ہیں اور بری حالت بن رہی ہے.مہمان نے کہا تم نے یہ
حالت کیوں بنارکھی ہے؟ عورت نے کہا تمہارے بھائی کو تو میری طرف کوئی توجہ نہیں.تمام
دن روزہ رکھتا ہے اور تمام رات نفل پڑھتا رہتا ہے.میں کس کی خاطر اپنی زینت کی طرف
توجہ کروں؟ یہ سن کر مہمان خاموش ہو گیا.شام کو اپنے دوست کے ساتھ کھانا کھایا اور عشاء کی
نماز کے بعد دونوں سو گئے.تھوڑی دیر ہوئی تو میز بان اٹھا.مہمان نے کہا کیا کرتے ہو؟
میزبان نے جواب دیا نفل پڑھنے کی تیاری کرتا ہوں.مہمان نے کہا سو جاؤ بھی تہجد کا وقت
نہیں ہوا.میزبان لیٹ گیا.پھر تھوڑی دیر بعد اٹھا اور مہمان نے پھر اصرار کیا کہ سو جاؤ.غرض متعدد بار یہی حالت ہوئی اور آخر جب تہجد کا وقت ہوا تو دونوں نے نفل پڑھے اور پھر
فجر کی نماز پڑھی.پھر میزبان نے مہمان کے سامنے کھانے کے لئے کچھ رکھا.مہمان نے
میزبان سے کہا تم بھی کھاؤ.میزبان نے عذر کیا کہ میرا تو روزہ ہے.مہمان نے کہا میں تو
جب کھاؤں گا جب تم بھی شامل ہو گے.عربوں میں چونکہ مہمان کا بہت احترام ہوتا ہے اور
روزہ نفلی تھا.میزبان نے روزہ کھول دیا اور ناشتہ میں شامل ہو گیا.پھر وہ رسول اللہ ﷺ کی
خدمت میں حاضر ہوئے.مہمان نے رات کا تمام قصہ حضور کی خدمت میں بیان کر دیا اور کہا
یا رسول اللہ ﷺ کیا میں نے ٹھیک کیا یا غلط کیا؟ آپ نے فرمایا تم نے ٹھیک کیا اور میزبان
کی طرف متوجہ ہو کر آپ نے فرمایا لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ
وَلِضَيْفِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ.یعنی تیری جان کا بھی تجھ پر حق ہے اور تیری بیوی کا بھی تجھ پر
حق ہے اور تیرے مہمان کا بھی تجھ پر حق ہے.75
Page 76
اسلام میں رہبانیت نہیں
آپ ﷺ نے رہبانیت سے منع فرمایا ہے اور فرمایا ہے کہ ہمارا طریق متابل
زندگی بسر کرنا ہے اور مومن کو چاہئے کہ اسی طریق کو اختیار کرے.آپ کا اپنا طریق بھی یہی تھا اور آپ کی تعلیم بھی یہی تھی کہ انسان دنیا سے کنارہ
کش ہو کر نہ بیٹھ جائے بلکہ دنیا میں رہے اور اپنے تمام فرائض اور حقوق جو اس کے ذمہ ہیں
احسن طریق سے ادا کرے لیکن دنیا کا نہ ہو جائے.دست با کار، دل بایار والا معاملہ ہو.اور
آپ کی اپنی زندگی اس کا کامل نمونہ تھی.آپ ایک دفعہ حضرت عائشہ کو نصیحت فرمار ہے
تھے کہ ہر انسان کے اندر ایک شیطان ہوتا ہے انسان کو اس کی شرارت سے آگاہ رہنا چاہئے.حضرت عائشہ نے دریافت کیا: کیا آپ کے اندر بھی شیطان ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا
ہاں.لیکن میرا شیطان بھی مسلمان ہو چکا ہے.مراد آپ کی یہ تھی کہ میرے نفس کی اپنی کوئی
خواہش باقی نہیں میں وہی کرتا ہوں جو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے.حقوق العباد
حقوق اور ذمہ داریوں کی ادائیگی کا آپ کو اس قدر خیال تھا کہ آخری بیماری میں
جب آپ کے وصال کا وقت قریب پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ جس کسی کا کوئی حق میرے ذمہ
ہو وہ اس وقت مجھ سے لے لے.تا کہ میں اپنے مولیٰ کے سامنے تمام ذمہ داریوں سے آزاد
ہو کر جاؤں.چنانچہ ایک شخص نے تعمیل ارشاد میں ایک چھوٹی سی رقم بتائی جو آپ کے ذمہ اس
کی نکلتی تھی اور آپ نے وہ فوراً ادا فرما دی.ایک اور موقعہ پر جب ایک جنگ میں صفیں سیدھی
کراتے ہوئے ایک مسلمان کو اتفاقاً آپ کے ہاتھ سے تیر لگ گیا.اس شخص نے عرض کیا یا
رسول اللہ ﷺ مجھے اس کا بدلہ ملنا چاہئے.آپ نے فرمایا تم بھی مجھے تیر مارلو.یہ سن کر بعض
76
Page 77
رض
صحابہ جو موجود تھے بیتاب ہو گئے.اس شخص نے عرض کیا یا رسول
اللہ ﷺ میرا بدن جہاں
مجھے تیر لگانا تھا اور آپ کا بدن ڈھکا ہوا ہے.آپ نے اپنے بدن مبارک سے کرتا اٹھایا
اور فرمایا لو اپنے ننگے بدن پر مارلو.وہ شخص فوراً آگے بڑھا اور آپ کے جسم مبارک پر بوسہ دیا
اور عرض کیا یا رسول اللہ بس میری اتنی ہی غرض تھی کہ اس بہانے سے آپ کے مبارک جسم کو
بوسہ دے لوں.غرض آپ ﷺ کے اخلاق کی کس قدر تفصیل بیان کی جائے.آپ زندگی کے ہر
شعبہ میں کامل نمونہ تھے.فِدَاهُ اَبِيْ وَ أُمِّی.23 مئی
حضرت مسیح موعود کی بعثت
امت محمدیہ بھی کس قدر خوش نصیب ہے.قرآن کریم جیسا کامل ہدایت نامہ اور
محمد ال جیسا کامل بادی.لیکن افسوس کہ مسلمانوں نے قرآن کریم کو بند کر کے رکھ دیا اور
رسول اللہ ﷺ کے نمونہ کو بھول گئے.تفاسیر کے رطب و یابس کے پیچھے پڑ گئے.اور
قبر پرستی اور تو ہم پرستی اور رسوم و رواج کی زنجیروں اور بیڑیوں میں پھنس گئے.حتی کہ
رسول اللہ ﷺ کے قول کے مطابق قرآن کریم کی صرف عبارت ہی باقی رہ گئی اور اسلام کا
صرف نام ہی باقی رہ گیا.تب اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی اور اپنے وعدہ کے مطابق اس
نے رسول اللہ ﷺ کے ایک بچے اور جاں نثار خادم کو تجدید اسلام کے لئے مبعوث کیا تا وہ
اسلام کے خوش نما چہرے سے تمام وہ دھبے دور کر دے جو مسلمانوں کی غفلت کی وجہ سے
بصورت غلط عقائد اور غلط حاشیہ آرائی کے اس پر جمع ہو گئے تھے.اور قرآن کریم کے صحیح علوم کا
چشمہ پھر جاری کر دے تا دنیا روحانی آب حیات سے سیراب ہو سکے اور وہ اپنی زندگی سے
اسلامی طرز حیات کا نمونہ پھر قائم کرے.اس زمانہ میں تو خود مسلمانوں کی یہ حالت ہے کہ وہ
77
Page 78
عذر کرنے لگ گئے ہیں کہ دنیا کی طرز اس قدر بدل چکی ہے کہ اسلامی تمدن اور اسلامی
معاشرت اپنے اصلی رنگ میں قائم نہیں رہ سکتے.اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود
بانی سلسلہ احمدیہ کو اس زمانہ میں مبعوث فرمایا تا آپ کے ذریعہ سے اسلام کی ترقی کے نئے
دور کی بنیا درکھی جائے.اور اسلام پھر اپنی آب و تاب میں ظاہر ہو.صلى الله
مسلمانوں کی طرف سے بڑا اعتراض جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دعوئی پر کیا
جاتا ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے بعد نبی نہیں آسکتا.اور حضرت مسیح موعود
علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے.یہ ایک لمبا مسئلہ ہے.لیکن مختصر طور پر ذہن
نشین کر لینا چاہئے کہ قرآن کریم آخری شریعت ہے اور چونکہ یہ ہر رنگ میں کامل ہے اس
لئے اس کے بعد کسی نئی شریعت کی ضرورت نہیں اور نہ کوئی نیا شارع نبی آسکتا ہے جو اسلامی
شریعت کو منسوخ کرے یا اس کی ترمیم کرے.اور نہ کوئی ایسا نبی آسکتا ہے جس کو بغیر اتباع
نبی کریم ﷺہ نبوت کا درجہ عطا ہو کیونکہ بجز آپ کی اتباع کے اور قرآن کریم پر عمل کرنے
کے کوئی شخص مومن بھی نہیں بن سکتا.چہ جائیکہ اعلیٰ ترین روحانی انعام یعنی درجہ نبوت کو پاسکے
لیکن اس رنگ میں نبی آسکتا ہے کہ وہ اتباع نبی مہ میں فنا فی الرسول کا مقام حاصل
کرلے.اور اللہ تعالیٰ اسے کثرتِ مکالمہ، مخاطبہ سے مشرف فرمائے اور اسے تجدید اسلام
کے لئے مقرر فرمائے اور اسے نبوت کا درجہ عطا فرمائے کیونکہ ایسی نبوت رسول اللہ ﷺ کی
نبوت کا ہی ظل اور جزو ہے.اور حضور ﷺ کی نبوت سے الگ نہیں.اور ایسی نبوت امت
محمدیہ کے لئے ایک رحمت ہے اور ختم نبوت کے منافی نہیں.اور امت محمدیہ کو دوسری امتوں
سے ممتاز کرتی ہے.کیونکہ ان کی تعلیمیں اور شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں اور ان کی تجدید اور
احیاء کے لئے اب کسی خاص انتظام کی ضرورت نہیں.لیکن قرآن کریم زندہ ہے اور منسوخ
نہیں ہوسکتا.اور اس کی باطنی حفاظت کے لئے اور اس کی تعلیم کے مطابق نمونہ قائم کرنے
کے لئے ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے احیاء کا انتظام ہو سو وہ ظلی نبوت کا
سلسلہ ہے جو اس امت میں جاری ہے.78
Page 79
حضرت مسیح موعودؓ سے پہلے اسلام کی نازک حالت
حضرت مسیح موعود کی بعثت سے قبل اسلام نہایت ضعف کی حالت کو پہنچ چکا تھا.مسلمانوں کے دلوں سے دین کی محبت اٹھ چکی تھی.قرآن کریم کا علم جاتا رہا تھا.اعمال پر
تو ہم پرستی اور رسم و رواج قابو پاچکے تھے اور مسلمان دن بدن قعر مذلت میں گرتے چلے
جارہے تھے.آپ نے اسلام کی حمایت کا بیڑ اٹھایا اور اللہ تعالی کی تائید اور اس کی دی ہوئی
توفیق کے ساتھ اسلام کو نئے سرے سے جاری کیا اور اس میں زندگی کی روح پھونکی.قرآن کریم کے علوم کا چشمہ پھر جاری کیا اور چند سال کے دوران میں براہین قاطعہ کے ساتھ
اسلام کی دیگر ادیان پر برتری ثابت کر کے دکھا دی.حتی کہ آج مسلمان پھر فخر سے اپنی
گردنیں بلند کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ایسا الہی ہدایت نامہ ہے جو دنیا کے ہر مرض اور
ہر دکھ کا علاج تجویز کرتا ہے اور جس پر عمل کر کے انسان اپنی زندگی کے مقصد کو پہنچ جاتا ہے.اور ہم نے اللہ تعالیٰ کے اس وعدہ کو اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا دیکھ لیا.ہم نے ہی قرآن کریم
کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کا انتظام کریں گے.حضرت مسیح موعود پر آنحضرت عل اللہ کا فیضان
یہ سب کچھ جو ہوا دراصل رسول اللہ ﷺ ہی کا فیضان ہے.جیسے حضر
مسیح موعود نے متعدد مقامات پر فرمایا ہے.مثلاً
جان و دلم فدائے جمال محمد است
نثار کوچه آل
آل محمد
خاکم
دیدم
در
بعین
قلبب
و
شنیدم بگوش ہوش
ہر مکاں ندائے جمال محمد
79
Page 80
این
چشمہ رواں که خلق خدا دہم
یک قطره زجر کمال محمد
این آتشم زآتش
میر محمدی
دیں آپ من ز آب زلال محمد است
پھر فرمایا :-
بعد
از
خدا
گر کفر ایں
این بود
بعشق محمد محترم
بخدا سخت کافرم
ہر تار و پودے من بسرائد بعشق او
از غم آن دلستاں پُرم
از خود تهی
و
جانم فدا
شود
دین
بره
مصطفى
این است کام دل اگر آید میسرم
پھر
فرمایا :-
نامش مصطفی
آں
عشاق
حق
الضحی
آں کہ
نورے
ہر
آں کہ
منظور
خدا
تھیں
منظور
نور اوست
اوست
آں کہ بحر
زندگی آب
روال
در
معارف
ہمیچو
بحر
بیکراں
در جہاں
آں کہ بر صدق
بر صدق و کمالش
حبت روشن عیاں
کہ انوار خدا
دلیل
و
آں
ظہر
کار
خدائی
پر
روئے
او
کوئے
او
80
Page 81
آں کہ
جمله
انبیا
و
راستاں
خادمانش
ہمچو خاک
آں کہ مهرش می رساند تا
آستاں
سما
میکند
چوں ماه تاباں در
صفا
پھر فرمایا :-
شان احمد را که داند جز خداوند کریم
آنچنان از خود جدا شد کرمیاں افتاد میم
شد مجو دلبر کز کمال اتحاد
زاں نمط
پیکر اوشد سراسر صورت رب رحیم
ہوئے محبوب حقیقی میدمدزاں روئے پاک
ذات حقانی صفاتش مظہر ذات قدیم
گر چه منسوبم کند کس سوئے الحاد و ضلال
چوں دل احمد نمی بینم دگر عرش عظیم
در
این
پھر فرمایا :-
رو
عشق محمد این سرو جانم رود
تمنا ایں دعا این در دلم عزم صمیم
فضل
خدا
پیشوا
مامسلمانیم
از
مصطفى
مارا
امام
و
اندریں
دیس
آمده
از
مادریم
ہم
بریس
از
دارد نیا
بگذریم
81
Page 82
از کتاب حق که قرآن نام
اوست
بادة
عرفان ما
آں رسولی کش محمدم
پاکش
از
جام
اوست
نام
دامن
مہر
بدست
ما مدام
او
باشیر
شد اندر
بدن
جاں شد و با جان بدر
بست
خواہد
شدن
خیر الرسل
خیر الانام
ہر
نبور
از و نو
نو شیم
زد
برو شد اختتام
شده سیراب سیرابے کہ
ہر
آنچه
مارا وحی و
ایمائے
بود
آں نہ
از خود از ہماں جائے بود
し
ازو
یا نیم
ہر
نورو کمال
وصل
دلدار
ازل
ہے
او
محال
اقتدائے
قول
او در جانِ
ہر چہ
زو
شود ایمان
آنحضرت کے ساتھ حضرت مسیح موعود کا عشق
عہ
علوم
اور آپ نے اپنے آقا کے عشق سے بیتاب ہو کر فرمایا :-
نوریست
در جانِ
لعلیست
در
کان
82
Page 83
زظلمتہائے
گردد
دل آنگه شود
از
محبان
صاف
ぶ
را
عجب دارم دل آں ناکساں
تابنده از خوان محمد
رو
یچ
تھے
در دو عالم
ندانم
که
دارد
شوکت
و
شان
محمد
اگر
خواہی
نجات از
مستی
بیادر
ذیل
مستان
اگر خواہی
که حق
گوید
شنایت
بشو
از ول
شنا
خوان
محمد
خواہی
عاشقش
بست
برہان
دارم
فدائ
خاک
احمد
دلم
وقت
قربان
ہر
بگیسو
رسول
الله
که
شار
روئے
تابان
گر
دریں
ره
گندم
ور بسوزند
نتابم
رو
ز
ایوان
بکار
دیں
ترسم
از
جہانے
دارم
رنگ
ایمان
محمد
سهلست
از
دنیا
بریدن
بیادِ
حسن
و
احسان
محمد
83
Page 84
فدا
شد در رهش
ورة
ہر
دیدم
حسن
پنهان
دگر
استاد
نامے
ندانم
خواندم
در دبستان
محمد
بدیگر
کارے
ندارم
دلبرے
که
گشته
آن
چشم
آں
بیاید
نخواهم
جز
گلستان
پہلویم
دل
زارم
تیمش
بدامان
آں خوش
خوش مرغ از مرغان
دارد
جا
بستان
تو
جان
منور
شهردى
از عشق
P
فدایت
جانم
اے
محمد
جان
دریغا گرد هم
صد
جاں
دریں
راه
بنا
شد نیز
شایان
محمد
ہا
بدادند ایں
جوال
را
بمیدان
مولی
کردند
ره
بجو
در
آل
الا
اے
منکر
از
سلام
از
نور
84
داعوان
شان
نمایان
محمد
محمد
Page 85
کرامت گرچه
بے نام
و
نشان است
ز
غلمان
بيا
پھر فرمایا :-
در دلم
آنکه
جو
شنائے
سرورے
در
خوبی
ندارد
ہمسرے
آنکه
جانش
عاشق
یار
ازل
آنکه روحش واصل
آں
دلبری
آنکه
مجذوب
عنایات حق
ہیچو
طفل
وریده
در بری
آنکه
در برو
بحر
عظیم
آنکه
در
لطف
یکتا
ورے
آنکه
در
جود
و سخا
بہار
آنکه
در
وعطا
یک خاوری
آں رحیم
رحم حق
آیتے
اں کریم
جود
حق
مظہرے
آن رخ فرخ کہ
دیدار أو
زشت
رو
را
میکند
خوش منظرے
آں دل روشن که روشن کرده است
صد
درون
تیره
چوں اخترے
آں مبارک که آمد ذات أو
پے
رحمتے
زاں
ذات
85
پروری
Page 86
احمد
آخر
زماں
کر
نور أو
شد
دل مردم
زخور تاباں
ترے
از
بنی آدم
فزوں
تر در جمال
وز لالی
پاک
تر
در
گوہرے
ليش
جاری
ز حکمت
در دلش
بہر حق
از
معارف
کوثرے
پر
داماں زغیرش
پر
نشاند
ثانیئے
او
نیست
در بحر و برے
آں
چراغش داد حق کش
ابد
خطر
نے
زیاد
مرمرے
پہلوان
حضرت
جلیل
پر
میاں
بسته
ز شوکت خنجرے
تیر
او
تیزی
بہر
میداں
نمود
او ہر جا نموده جو ہرے
کرد
ثابت
پر
جہاں عجز بُتاں
وانموده
زور
آں یک
قادری
عاشق
صدق
و
سداد
راستی
و
فساد
و
ہر شرے
را
بنده
دشمن
خواجه
پادشاه
كذب
و
مرعا جزاں
و بیکساں
را چا
آں تر جمہا کہ خلق از وے
بدید
ندیده در
جہاں از
مادری
86
Page 87
روشنی
از
دے
بہر قوم
رسید
نور
أو
زشید
ہر
کشوری
آیت
رحماں
برائے
ہر
بصیر
حق
بہر
ہر
دیده
ورے
ناتواناں
را
برحمت
جاناں
را به
غمخورے
رویش
زماه
و
نہ
آفتاب
خاک کوئیش ز مشک و
عنبرے
آفتاب
ماند
برو
درویش
از
نور حق
تیرے
بہتر
زعمر
جاوداں
گرفتند
را بر آن خوش
خوش پیکرے
منگه
از
حسنش
ہمی دارم
جاں فشانم
ངམ
دید
دل دیگرے
یاد آں
صورت
از
خود
برد
ہر
می
زمان مستم کند از
پریدم سوئے کوئے
من اگر میداشتم بال
امی
زیں
آں
و
J.مجھے روشن ترے
شراب معرفت
کز شعاعش خیر
خیر شد
دادش
ہر
خدا
اخترے
ساغرے
او
مدام
87
Page 88
شد عیاں از دے
جو ہر انسان که بود
على الوجه
الا تم
آں
مضمرے
ختم شد
نفس پاکش
ہر
کمال
لا جرم
شد
پیغمبرے
ہر
آفتاب
ہر
زمین
و ہر زماں
اسود
ہر احمرے
ہر
البحرین.معرفت
الامین
خاورے
چشم
من
بسیار گردید
و
ندید
چشمه
چوں
دمین او صافی نزے
سالکاں
را نیست غیر از
وے
امام
رہرواں
را نیست جزوے
رہبرے
یک طرف حیران از و شاہان وقت
یک طرف مبهوت دانش
ہر
ورے
بعلمش کس
رسیدونی
بزور
در شکسته
ہر
دارد
چه
بمرح
متکبری
کس نیاز
مدح او خود
خود فخر
ہر
مدحت
بست
او
در
روضه
گرے
قدس و جلال
وز خیال
مادحاں
بالا
ترے
اے
خدا
بروے
سلام
مارساں
برا
خوانش
زہر
پیغمبرے
88
Page 89
ہر رسولے
ہر
ہر رسولی
رسولے
آفتاب
صدق
بود
انورے
بود
بود
كات
دیں
یناه
ہر رسولی
بود
باغ
مثمرے
گر بدنیا
نامدے
اس
پاک
کار دیں
ماند
سراسر
ابترے
احمد
است
اول آدم آخر شاں
اے خنک آں کس که بیند آخرے
انبیاء
روشن
ہست
احمد
هستند
لیک
زاں ہمہ روشن ترے
آپ نے اردو، فارسی اور عربی میں بے مثال نعتیں اور قصائد حضور کی شان میں
لکھے ہیں اور آپ کی سب تحریریں حضور کے عشق میں ڈوبی ہوئی ہیں.آپ کی تمام زندگی اس
تڑپ میں گزری کہ اپنے آقا ﷺ کے باغ کی آبپاشی کا انتظام خاطر خواہ فرما دیں اور اسے
ہرا بھرا دیکھ لیں جیسے آپ نے فرمایا :-
این دو فکر دین احمد مغز جان ما گداخت
کثرت اعدائے ملت قلت انصار دیں
اور پھر فرمایا:-
کے اندر نماز خود دعائے می کند
من دعا ہائے بروبار تو اے باغ بہار
اور پھر فرمایا :-
کنید
دوستان خود را نثار حضرت جاناں
درره آن یار جانی جان و دل قرباں کنید
89
Page 90
آں دل خوشباش را کاندر جہاں جوید خوشی
از لیئے دین
محمد کلبه احزاں کنید
از میں ہا بروں آئید اے مردان حق
خویشتن را از پینے اسلام سرگرداں کنید
اور آپ کی اپنی زندگی کی کیفیت کسی قدر آپ کے اس قول سے معلوم ہوسکتی ہے:.نمی ترسیم از مُردن چنیں خوف از دل افگندیم
کہ مامردیم ازاں روزے کہ دل از غیر برکندیم
دل وجاں درره آن داستان خود فدا کردیم
اگر جاں باز ما خواهد بصد دل آرزو مندیم
اسلام کا دوسرا دور
آخر حضرت مسیح موعود نے اسلام کے غلبہ کا دوسرا دور شروع ہوتا دیکھ لیا.اور آپ
کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی جماعت کی بنیاد ڈال دی جس کا ہر فرد اسلام کی خاطر
جان قربان کرنے کے لئے تیار ہے اور جو دن رات اسلام کی ترقی کے لئے کوشاں رہتی ہے.اور جس کے ہاتھوں ان علوم اور دلائل کے ذریعہ جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر
کھولے گئے اور جنہیں آپ نے اسلام کی تائید میں پیش کیا، اسلام کا دوبارہ غلبہ مقدر ہے.آپ نے ایک نئے علم کلام کی بنیاد ڈالی اور نئے نئے علوم قرآن کریم سے نکال کر
پیش کئے.اور نئے نئے دلائل کے ساتھ اسلام کی صداقت کو ثابت کیا اور وہ روحانی چشمہ جسے
آپ نے جاری فرمایا اس وقت زور شور سے بہہ رہا ہے اور حق کی تڑپ رکھنے والوں کی پیاس
بجھانے اور انہیں فرحت و تازگی اور توانائی بخشنے کا کام بھی دے رہا ہے.90
Page 91
اور میری غرض اس ایک لحاظ سے لمبی اور ایک لحاظ سے مختصر تحریر سے یہ ہے کہ تمہیں
بھی اس چشمہ کی حقیقی شناخت ہو جائے اور تمہارے دل میں اس کا شوق پیدا ہو جائے.اور تم
خود اس چشمہ سے جا کر سیراب ہو اور صرف دوسروں کے ذریعہ چلو بھر پانی حاصل کرنے پر
قانع نہ رہو.یہ وہی چشمہ ہے جو آج سے ساڑھے تیرہ صد سال قبل عرب کی سرزمین
میں وادی بطحا میں پھوٹا اور پھر ہمارے زمانہ میں پنجاب کی سرزمین میں قادیان کی بستی میں
پھوٹا ہے.اس کا پانی ٹھنڈا اور میٹھا اور زندگی بخش ہے.جو شخص اس چشمہ سے سیراب ہوا
اس نے ہمیشہ کی زندگی حاصل کر لی اور جو اس سے محروم رہا اس نے تپش اور سوزش اور کرب کو
اپنا حصہ بنایا.حضرت مسیح موعود فرماتے ہیں:
آؤ لوگو کہ یہیں نورِ خدا پاؤ گے
تمہیں طور تسلّی کا بتایا ہم نے
دیکھو دنیا میں اس وقت کس قدر کرب و بے چینی ہے.امن اور اطمینان اٹھ گیا ہے.بنی نوع انسان ہراساں ہے.اور نہیں جانتے کہ کہاں اور کس طرح حقیقی تسلی پائیں.سب
امن کے متلاشی ہیں لیکن امن کو پا نہیں سکتے.اطمینان چاہتے ہیں لیکن اطمینان ان سے روک
دیا گیا ہے.بظاہر وہ کونسی نعمت ہے جو آج دنیا کو میسر نہیں.پچھلے زمانوں کے مقابلہ
میں انسان کی زندگی آج زمین پر نہایت آرام اور اطمینان کی زندگی ہونی چاہئے اور یہی زمین
بہشت کا نمونہ ہونی چاہئے لیکن یہ زمین دوزخ کا نمونہ بن رہی ہے.جن قوموں کو
تہذیب و تمدن اور شائستگی کا سب سے بڑھ کر دعویٰ ہے وہی امن کی بربادی کے در پے ہیں
اور انسان کے دکھ اور ضرر اور اس کی موت اور تباہی کے سامان دیوانوں کی طرح تیار کر رہے
ہیں.یہ اس لئے ہوا کہ انسان نے امن حاصل کرنے کا وہ رستہ چھوڑ دیا جو اللہ تعالیٰ نے مقرر
فرمایا تھا اور اپنے خود تراشے ہوئے رستوں کو اختیار کیا اور ان رستوں پر چلتے چلتے انسان
بجائے امن کی وادی میں پہنچنے کے خوف اور ملال اور بے چینی اور جوش اور فساد اور ہلاکت کی
وادی میں پہنچ گیا.لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے ہاتھوں کی کمائی کے نتیجہ میں ہلاکت کے
91
Page 92
منہ میں نہیں چھوڑ دیا.اس نے اپنے رحم سے اس کی نجات کا رستہ کھولا ہے اور جو بھی اس رستہ
کو شناخت کرتا اور اس پر گامزن ہوتا ہے وہ یقیناً امن واطمینان اور سکون اور خوشی اور راحت
اور ابدی زندگی کی وادی میں پہنچ جائے گا.لیکن جو افراد یا قو میں اس رستہ سے منہ موڑتی ہیں
اور اپنے دماغوں کی تجویز کردہ تدابیر اختیار کرتی ہیں اور اللہ تعالی کی آواز پر کان نہیں دھر تیں
وہ ضرور ضرور ہلاک ہوں گی اور ان کا ذکر دنیا کی تاریخ میں اسی طور پر رہ جائے گا جیسے عاد و ثمود
اور فرعون کی قوم اور رومیوں اور یونانیوں اور ایرانیوں کا ذکر.سائنس اور مذہب
یہاں تک تو ایمان اور عقائد کا ذکر تھا اب میں عملی حصہ کے متعلق کچھ بیان کرتا ہوں.لیکن اس سے قبل شاید اس امر سے متعلق کچھ وضاحت کر دینی مفید ہو گی.آج کل ایک رو
چل پڑی ہے کہ جس بات سے متعلق ہمیں سائنس کی تائید نہ مل سکے اسے یا تو رد کر دیا جاتا
ہے یا مشکوک قرار دے دیا جاتا ہے.حالانکہ سائنس خود ایک نامکمل حالت میں ہے اور روز
بروز ہمارے علم میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے.اس لئے ہم نہیں کہہ سکتے کہ آج جو فیصلہ
سائنس کا کسی بات سے متعلق ہے وہ قطعی اور یقینی ہے.میں مثال کے طور پر بیان کرتا ہوں کہ
قرآن کریم میں ذکر ہے کہ لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں ان کے خلاف آخرت میں شہادت دیں
گے.سینما کی ایجاد سے قبل اس حقیقت کا سائنس کی بناء پر سمجھنا مشکل تھالیکن سینما نے یہ
حقیقت واضح کر دی.جو لوگ سینما دیکھنے کے لئے جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ کس طور پر ہاتھ
اور پاؤں کی شہادت محفوظ کی جاسکتی ہے اور پھر لوگوں کو دکھائی جاسکتی ہے.حتی کہ ایک ایکٹر
خود جا کر اس تصویر کو دیکھ سکتا اور اپنے ہاتھ پاؤں کی حرکات کا اندازہ لگا سکتا ہے جس میں وہ
حصہ لے چکا ہوتا ہے.جب بادشاہ جارج پنجم 1911ء میں ہندوستان تشریف لائے اور
دہلی میں تاج پوشی کا دربار ہوا تو دربار کی تصویر لی گئی اور بعد میں بہت عرصہ وہ لندن میں
92
Page 93
دکھائی جاتی رہی اور بادشاہ سلامت اور ملکہ اور شہزادے اور شہزادیاں سب دیکھنے جاتے
رہے.ایک موقع پر بادشاہ سلامت اپنی والدہ صاحبہ کو دکھانے کے لیئے اپنے ساتھ لے
گئے.اس وقت ملکہ الیگزینڈرا تاج پوشی کا دربار جودہلی میں ہو ا دیکھ رہی تھیں.تصویر میں بھی
بادشاہ اور ملکہ انہیں نظر آرہے تھے اور بادشاہ سلامت ان کے پاس بھی بیٹھے ہوئے انہیں بتا
رہے تھے کہ دیکھو اس موقع پر یوں ہوا اور اس موقع پر یوں ہوا.گویا گذشتہ کا سارا فعل مجسم
ہوکرسامنے آگیا.اسی طرح جب تک ریڈیو کی ایجاد کمل نہ ہوئی تھی الہام اور وحی کے مسئلہ کا سمجھنا محض
عقل کی بناء پر اور سائنس کی بناء پر مشکل تھا.لیکن اب تو گھر گھر ریڈیو لگ گیا ہے اور الہام
اور وحی کا مسئلہ انسانوں کے فہم کے زیادہ قریب ہو گیا ہے.ملائکہ کا وجود
لیکن فرشتوں کے وجود کا سمجھنا ابھی تک انسانی ذہن کے لئے مشکل ہے.میں ا.ذوق کے مطابق ایک مثال دیگر تمہیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں.گو یہ مثال میں محض
سمجھانے کے لئے استعمال کر رہا ہوں تفصیلی طور پر اس مسئلہ کو تم حضرت خلیفتہ اسیح الثانی کی
تقریر ملا ئکتہ اللہ پڑھ کر سمجھ سکتے ہو.میں کہہ چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک وراء الوراء اور لطیف در لطیف ہستی ہے اور انسان
ایک مادی اور کثیف ہستی ہے.گو اس کی لطیف دماغی اور روحانی طاقتیں اور احساس بھی ہیں
لیکن پھر بھی انسان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان براہ راست اور بلا واسط تعلق مشکل ہے.انسانی
قومی ایسے تعلق کی برداشت نہیں رکھتے.جیسے قرآن کریم میں ذکر آتا ہے کہ حضرت موسیٰ نے
اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کی کہ میں آپ کو دیکھنے کی خواہش رکھتا ہوں.تو جواب ملا کہ تم مجھے
دیکھنے کی طاقت اور برداشت نہیں رکھتے لیکن اس پہاڑ کی طرف دیکھو اس پر میری تجلی ڈالی
93
Page 94
جائے گی.اور جب پہاڑ پر اللہ تعالیٰ کے نور کی تجلی ہوئی تو پہاڑ پر زلزلہ آ گیا اور حضرت موسیٰ
بیہوش ہو کر گر پڑے.اس کی مثال ایسی ہے جیسے بجلی کی زبر دست روکا تار ہو جس میں سے بجلی
اپنے پورے زور سے گزر رہی ہو اگر اس تار کے ساتھ لیمپوں یا پنکھوں بلکہ کارخانوں کا جوڑ
کر دیا جائے تو وہ تیز اور طاقت ور روسب کچھ جلا دے گی.اسلئے جب اس بجلی کو استعمال کرنا
مقصود ہوتا ہے تو پہلے اس کی طاقت کم کی جاتی ہے.پھر اور کم کی جاتی ہے یہاں تک کہ اس کی
طاقت ایسے پیمانہ پر آجاتی ہے جسے لیمپ اور پنکھے اور انگیٹھیاں اور چھوٹی چھوٹی موٹروں کی
تاریں اور پرزے برداشت کر سکتے ہیں.اور پھر اس کے بعد اس بجلی کا استعمال ان اغراض
کے لئے کیا جاتا ہے.اس مثال سے فرشتوں کا وجود انسانی فہم سے قریب ہو جاتا ہے.موٹے طور پر سمجھ لو
کہ فرشتے ایک لطیف وجود ہیں جو انسان کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان واسطہ بن کر انسان کا
اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ممکن کر دیتے ہیں.یہ ایک موٹی تشریح ہے اور جیسے میں نے کہا ہے اگر
تم ملائکہ کے متعلق تفصیلی علم حاصل کرنا چاہو تو حضرت خلیفتہ اسیح الثانی کی وہ تقریر پڑھ لو جس
کا میں نے ذکر کیا ہے.روحانی اصلاح میں نماز کا مقام
انسان کی روحانی اصلاح اور ترقی کے لئے اسلام نے جن اعمال پر سب سے زیادہ
زوردیا ہے وہ نماز، ذکر الہی اور دعا ہیں.نماز کی اہمیت اس مثال سے واضح ہو جائے گی کہ نماز
کے اوقات پر گویا اللہ تعالیٰ کا دربار لگتا ہے اور سب درباریوں کو حاضری کا حکم ہوتا ہے اور
خلعتیں اور انعام تقسیم ہوتے ہیں اور عرضیں سنی جاتی ہیں اور قرب الہی کی منازل طے ہوتی
ہیں.اس دربار سے جو در باری غیر حاضر رہتا ہے وہ قابل مواخذہ ہے.اور نمازوں میں فرض
نماز کا حصہ گویا در بار خاص کا حصہ ہوتا ہے اور باقی حصے گویا دربار عام کی طرح ہوتے ہیں.94
Page 95
انسان کو چاہئے کہ ان اوقات کا منتظر رہے اور وقت آنے پر عاشقانہ شوق سے دربار کے لئے
تیاری کرے.اپنے بدن کی صفائی کرے.صاف اور پاکیزہ لباس ہو اور پھر دربار کے
آداب کے مطابق بر وقت اور با ادب حاضر ہو جائے اور جب تک دربار سے رخصت کی
اجازت نہ مل جائے حاضر رہے اور اپنی عرض معروضات پیش کرے اور اس راز و نیاز کے
موقع سے فائدہ اٹھا کر قرب الہی کی منازل طے کرنے کی کوشش کرے.اور جب ایک دربار
سے رخصت کی اجازت ملے تو پھر اپنے معمولی کاروبار کی طرف متوجہ ہو جائے.لیکن جس
دربار سے ابھی واپس آیا ہے اس کا ذوق دل و دماغ کو معطر کر رہا ہو اور دوسرے دربار میں
بلائے جانے کی انتظار میں ہو.اور دل میں ایک شوق اور ولولہ اور بے صبری ہو کہ کب پھر
دربار میں بلاوا ہو اور میں بصد شوق پھر حاضر ہو جاؤں.اور اس درمیانی وقفہ میں گو
دست با کار ہومگر دل بایار ہو.اور محبوب حقیقی کا نام دل سے اٹھ اٹھ کر بے اختیار بار بار زبان
پر آئے اور اس طرح گویا نمازوں کے درمیان بھی ذکر الہی جاری رہے.جیسے حضرت
خلیفہ اسیح الثانی نے فرمایا ہے:
عادت ذکر بھی ڈالو کہ یہ ممکن ہی نہیں
دل میں ہو عشقِ صنم ، لب پہ مگر نام نہ ہو
چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات پر غور ہوتا رہے اور اس کے احسانات کی یاد بار بار کی
جائے اور اگر فجر کی نماز کے بعد کا وقت ہے تو صحیفہ الہی یعنی قرآن مجید میں سے جس قدر میسر
ہو پڑھا جائے اور اس پر غور کیا جائے.اور پھر اگر موقع ہو تو انسان دعا میں لگ جائے.اور دعا
کی مثال نماز کے مقابل میں ایسی ہے کہ اصل دعا کا وقت تو نماز ہے جب کہ انسان در بارالہی
میں حاضر ہوتا ہے اور ہر ایک درباری کو حاضری کا حکم ہے.لیکن بھلا ایک عاشق صادق اتنے
پر کب صبر کر سکتا ہے.وہ درمیان میں بھی بے قرار ہو کر خود جا کر دروازہ پر دستک دیتا ہے اور
دعا کرتا اور گڑ گڑاتا اور آہ وزاری کرتا ہے.یہ گویا نماز کے علاوہ اوقات کا ذکر الہی ہے.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے : میں ہر وقت اپنے بندوں کے قریب ہوں.اور ہر وقت ان کی پکار کو سنتا
95
Page 96
ہوں.اگر دن کا اس طرح سے آغاز ہوگا اور اس طرح دن گزرے گا اور ختم ہوگا اور رات کو
بھی کروٹ بدلنے پر اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جائے گا اور رات کا کچھ حصہ نوافل میں صرف ہوگا تو
انسان کی تمام زندگی گویا ایک مسلسل عبادت ہو جائے گی.اور دراصل یہی حالت ایک حقیقی
مومن کی زندگی کی ہونی چاہئے.اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل سے ایسی ہی زندگی کی تو فیق عطاء
فرمائے.آمین.اب سنو کہ نماز کی تیاری کس طرح کی جاتی ہے.پہلا حصہ اس تیاری کا ظاہری صفائی
کا ہے.اوّل تو انسان کو چاہئے کہ اپنے لباس کو صاف ستھرا اور پاکیزہ رکھے.کیونکہ گو
در بارالہی میں شاہ و گدا سب یکساں ہیں اور وہی زیادہ عزت پاتا ہے جس کا دل سب سے
زیادہ عشق الہی سے معمور ہوتا ہے اور اس دربار میں کوئی ظاہری تکلف نہیں.لیکن اس دربار
کے بھی بعض آداب ہیں اور ان میں سے سب سے پہلا امر ظاہری صفائی اور پاکیزگی ہے.لباس کی صفائی اور پاکیزگی کے بعد انسان کو اپنے بدن کی صفائی کی طرف توجہ کرنی چاہئے.رسول اللہ ﷺ نے مسواک کا استعمال ہر مومن کے لئے ضروری قرار دیا ہے اور اس کو اس
قدر اہمیت دی ہے کہ فرمایا کہ اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ یہ امر میری امت پر شاید بوجھ
ہو جائے تو میں ہر نماز کے وقت مسواک لازم قرار دیتا.وضو کی تفاصیل تو تم جانتے ہی ہو.ان کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں.اس قدر
واضح کر دینا مناسب ہے کہ وضو کے فوائد اور اغراض میں سے بعض اعضاء کی ظاہری صفائی
بھی ہے اور یہ بھی ہے کہ وضو گویا ایک ظاہری نشان باطنی صفائی کا بھی ہے.ایک نمازی جب
نماز کی نیت سے وضو کرتا ہے تو جیسے وہ ظاہری اعضاء کو صاف کرتا ہے ویسی ہی وہ باطنی صفائی
کی طرف بھی توجہ کرتا ہے اور اپنے دل و دماغ کو دنیاوی خیالات سے پاک کرتا ہے اور اپنی
روح کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضری کی طرف متوجہ کرتا ہے.اور یوں بھی جسم کے جوارح
کو پانی سے دھونے کا یہ اثر ہوتا ہے کہ انسان کے خیالات کا انتشار دور ہو جاتا ہے اور اس کا
ذہن ایک طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور کاروبار اور بدنی محنت کی کوفت دور ہو کر ایک شگفتگی
96
Page 97
انسان کی طبیعت میں پیدا ہو جاتی ہے.نماز کے فوائد میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر نماز اپنے پورے لوازم کے ساتھ
سنوار کر ادا کی جائے تو انسان کے خیالات اور اعمال کو پاکیزہ بنادیتی ہے.جیسے قرآن کریم
میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: إِنَّ الصَّلوةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَر - یعنی نماز انسان
کو فحشاء اور منکر سے بچاتی ہے.پھر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ جو شخص با قاعدہ نماز ادا کرتا ہے اس کی مثال تو
ایسی ہے کہ گویا اس کے دروازہ پر مصفا پانی کی ایک نہر بہتی ہے جس میں وہ دن بھر میں پانچ
بار غسل کرتا ہے.مطلب آپ
کا یہ تھا کہ جس طرح دن میں پانچ مرتبہ غسل کرنے والے کہ
بدن پر میل نہیں رہ سکتی اسی طرح درست طریق پر نماز ادا کرنے والے کی روح بھی کبھی میلی
نہیں رہ سکتی کیونکہ نماز روحانی غسل کا رنگ رکھتی ہے.نمازوں کے مختلف اوقات تم کو معلوم ہیں اور نمازوں کی تقسیم بھی تم جانتے ہو.نماز
سے متعلق بعض امور کی جن پر بعض دفعہ اعتراض کیا جاتا ہے میں وضاحت کرنے کی کوشش
کرتا ہوں.اول یہ کہ نماز کی ظاہری حرکات یعنی قیام، رکوع ، سجدہ وغیرہ کی کیا اغراض ہیں
اگر نماز کی اصل غرض روح اور قلب سے تعلق رکھتی ہے تو ان ظاہری اور جسمانی حرکات کا کیا
فائدہ ہے ؟ اس کے جواب میں اول تو یا درکھنا چاہئے کہ انسان کے ظاہر اور باطن کا آپس میں
ایک گہرا تعلق ہے اور دونوں کا اثر ایک دوسرے پر پڑتا ہے.مثلاً انسان کا دل جب خوش ہوتا
ہے تو اس کے چہرے پر بھی اس خوشی کے آثار دکھائی دیتے ہیں اور بعض دفعہ وہ مسکرا دیتا ہے یا
ہنس بھی دیتا ہے.اور جب انسان کا دل غمگین ہوتا ہے تو اس کے چہرہ پر بھی غم کے نشان ظاہر
ہوتے ہیں یہاں تک کہ بعض دفعہ شدت غم میں اشک بار بھی ہو جاتا ہے.اسی طرح اگر ایک
مغموم آدمی کو بشاشت کی باتیں سنائی جائیں اور اسے تکلف سے بھی ہنسا دیا جائے تو کچھ
بوجھ اس کے
غم کا ہلکا ہو جاتا ہے.ایک شخص جب جوش اور غصہ کی حالت میں ہوتو وہ اگر بجز
سورة العنكبوت - آیت 46
97
Page 98
اور انکسار والی صورت بنائے اور ہاتھ باندھ کر ادب سے کھڑا ہو جائے تو اس کا جوش اور
غضب بھی ہلکا ہو جائے گا.اسی لئے نماز میں ادب اور انکسار کی حالتیں مقرر کی گئی ہیں کہ
جہاں نماز پڑھنے والے کا دل اس خیال سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہے بجز اور انکسار
سے پُر ہے وہاں اس کی ظاہری حالت بھی ایسی ہی ہو.چنانچہ ان حالتوں میں دل کی حالت
جسم کی ظاہری حالت کے ذریعہ ظاہر ہوتی ہے اور جسمانی حالت دل کی حالت پر اثر ڈالتی
ہے.نماز میں پہلے انسان ہاتھ باندھ کر با ادب کھڑا ہوتا ہے.پھر جب اس کے دل میں
اللہ تعالیٰ کی محبت اور جوش مارتی ہے اور اس کا عجز و انکسار محبوب حقیقی کے حضور میں بڑھتا ہے تو
وہ بے قرار ہو کر رکوع میں چلا جاتا ہے اور جب اس سے بھی اس کی بے قراری بڑھتی ہے تو وہ
سجدہ میں گر جاتا ہے اور اپنا سر آستانہ الہی پر رکھ دیتا ہے.اور ایک رکعت کے پورا ہو جانے پر
نئے سرے سے اپنی عبودیت کا اظہار شروع کر دیتا ہے اور نماز میں جو جو حرکات اور مقامات
مقرر کئے گئے ہیں وہ عین ادب اور عجز و انکسار کا اظہار کرنے والے ہیں.اور مختلف مذاہب
نے جو جو درست طریق اس اظہار کے لئے اختیار کئے ہیں ان سب کا مجموعہ نماز میں ہے بلکہ
اس سے بڑھ کر.پھر بعض دفعہ یہ سوال کیا جاتا ہے کہ ہر نماز میں متعد در کعتیں اور سنتیں اور فرائض اور
نوافل کیوں مقرر کئے گئے ہیں؟ اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ تکرار کا اثر انسانی طبیعت پر مسلمیہ
ہے اور ایک حد تک تکرار کرنے سے انسان کے دل کی کیفیت زیادہ سے زیادہ اثر پذیر ہوتی
جاتی ہے اور اگر تو جہ سے نماز ادا کی جائے تو قلب انسانی زیادہ سے زیادہ متاثر ہوتا چلا
جاتا ہے اور اس کی عجز و تضرع کی حالت بڑھتی جاتی ہے.اور ظاہری مثال اس
کی یہ بھی دی
جاسکتی ہے کہ اگر نماز انسانی دماغ اور قلب کے لئے روحانی غذا ہے تو اس غذا کی بھی ایک
مقدار ہونی چاہئے جو دل اور دماغ کی سیری کے لئے کافی ہو یعنی قلب انسانی سے بیرونی
اثرات کو دور کر کے پھر اسے روحانی طور پر تازہ اور مصفی کر دے اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے
98
Page 99
کہ ایک حصہ نماز میں پوری توجہ یا پورا خشوع اور خضوع انسان کے دل میں پیدا نہیں ہوتا تو
دوسری رکعت میں اس کمی کو پورا کر لیا جاتا ہے اور اس طرح نماز کا ہر حصہ مکمل طور پر ادا ہوسکتا
ہے اور اس سے پورا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے.مثلاً ہم دیکھتے ہیں کہ عمدہ سے عمدہ غذا کا بھی
صرف ایک لقمہ ہی ہماری جسمانی سیری اور تر و تازگی کے لئے کافی نہیں ہوتا اور متعدد لقمے اور
ایک خاص مقدار غذا کی اس غرض کے پورا کرنے کے لئے ضروری ہوتی ہے.اسی طرح اس
روحانی غذا کی بھی صورت ہے.اور یہی جواب اس سوال کا بھی ہے کہ دن اور رات میں بار بار نماز کی تاکید کیوں کی
گئی ہے.کیونکہ جیسے انسانی جسم تھوڑے تھوڑے وقفہ پر کوفت اور خشکی محسوس کرنے لگتا ہے اور
اسے غذا کی ضرورت پڑتی ہے اسی طرح انسانی روح پر بھی تھوڑے تھوڑے عرصہ کے بعد
روحانی کوفت اور خشکی کا اثر ہونے لگتا ہے اور اسے تازگی حاصل کرنے کے لئے روحانی غذا
کی ضرورت پڑتی ہے.اور اس عام اعتراض کا جواب کہ ظاہری صورت پر کیوں زور دیا گیا ہے، یہ ہے کہ
بے شک اصل
چیز قلبی اور روحانی حضور اور بجز اور اضطرار اور خشوع اور خضوع ہے لیکن روح
کو قائم رکھنے کیلئے جسم کا قیام ضروری ہے.انسان کے لئے دودھ ایک غذا ہے لیکن دودھ کو
محفوظ رکھنے کیلئے برتن کی ضرورت ہے.اگر برتن تو ڑ دیا جائے تو دودھ بھی محفوظ نہیں رہ سکتا.ایسے ہی جب جسم پر موت آجاتی ہے تو روح بھی اپنی موجودہ حالت پر قائم نہیں رہ سکتی.نماز کی مختلف دعا ئیں تو تمہیں یاد ہی ہیں لیکن مجھے علم نہیں کہ ان
کا ترجمہ اور مفہوم کہاں
تک تم سمجھتے ہو ا سلئے میں اس جگہ نماز کے ضروری حصوں کا سادہ مفہوم بیان کر دیتا ہوں :
بسمِ اللهِ الرَّحمٰنِ الرَّحِيمِ اللہ کے نام کے ساتھ جس نے محض اپنے رحم سے
ہماری تربیت اور ترقی کے سب سامان مہیا کئے اور جو ہمارے اعمال کا عمدہ سے عمدہ بدلہ دیتا
ہے.سُبْحَنَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ.بے عیب ہے تو اے اللہ اور تو ہی حقیقی طور پر
99
Page 100
سب کمالات کا مالک ہے.وَتَبَارَكَ اسْمُکَ.اور برکت والا ہے تیرا نام.وَتَعَالَى جَدُّکَ.اور سب سے بلند ہے تیرا درجہ.وَلَا إِلهُ غَيْرُک.اور تیرے سوا کوئی ہستی پرستش کے لائق نہیں.اَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطنِ الرَّحِیم.میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے ساتھ شیطان سے
جور د کیا گیا ہے.( یعنی میں تمام برے اثرات اور خیالات سے جو اللہ تعالیٰ سے دور کرتے
ہیں اللہ تعالیٰ ہی کی پناہ میں آتا ہوں.)
اَلحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْن.سب کمالات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے جو تمام کائنات کو
بتدریج ترقی دے کر ادنیٰ حالت سے اعلیٰ حالت تک پہنچاتا ہے.الرَّحْمَنِ الرَّحِیم.اس کا ترجمہ اوپر گزر چکا ہے.مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ.جو اعمال کے بدلہ دینے کے اوقات اور زمانوں کا مالک ہے.إِيَّاكَ نَعْبُدُ.ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں ( یعنی تیری ہی رضا کو اپنا مقصود
ٹھہراتے ہیں اور تیرے ہی اخلاق کی پیروی کرنا چاہتے ہیں)
وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ.اور صرف تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں (صرف تیرا ہی سہارا
ڈھونڈتے ہیں)
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ہمیں سیدھا رستہ دکھا اور اس پر چلنے اور ترقی کرنے
کی ہمیں توفیق عطا فرما.صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِم.ایسے لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام کیا ( یعنی وہ
رستہ جس پر چل کر لوگ تیرے انعاموں کے وارث بنے )
غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِيْن.نہ ایسے لوگوں کا جن سے تو ناراض ہو گیا
اور نہ ایسے لوگوں کا جو ایک دفعہ ہدایت پر کار بند ہو کر بعد میں رستہ سے بھٹک گئے.( یعنی نہ تو
ہم اپنے اعمال سے تیرے غضب کو بھڑ کانے والے ہوں اور نہ بعد میں ہم رستہ گم کر دیں)
100
Page 101
سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِیمُ.میرا رب جو ہر قسم کی عظمت والا ہے ہر قسم کے عیب اور نقص
سے پاک ہے.سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللہ تعالیٰ اس کی پکار کو سنتا ہے ( دعا قبول کرتا ہے اس کی )
جو اس کی حمد کرتا ہے (اس کی صفات پر غور کرتا ہے اور پکار اٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں
تمام کمالات جمع ہیں)
رَبَّنا وَلَكَ الْحَمْدُ.اے ہمارے رب حقیقی اور کامل تعریف کا تو ہی مستحق ہے
کیونکہ تمام کمالات تیرے ہی اندر جمع ہیں.حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكاً فِيْهِ.کثیر ، پاک اور مبارک حمد کا مستحق
سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى.میرا رب جو سب سے بلند درجہ والا ہے ہر قسم کے عیب اور
نقص سے پاک ہے.التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ.زبان کی سب تعریفوں اور عبادتوں اور
جسم کی تمام عبادتوں اور تمام مالی قربانیوں اور عبادتوں کا اصل مستحق اللہ تعالیٰ ہی ہے.اَلسَّلامُ عَليكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحمةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ.سلامتی ہو تجھ پر اے نبی
اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو اور اس کی برکتیں تجھ پر ہوں.السَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِینَ.سلامتی ہو ہم پر اور اللہ تعالیٰ کے
تمام نیک بندوں پر.اَشْهَدُ اَنْ لا إِلَهَ إِلَّا الله - میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کی ذات کے سوا کوئی ہستی
قابل پرستش نہیں.اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُوْ لُهُ.اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ تعالیٰ کے
کہ
کامل عبد اللہ تعالیٰ کی صفات کا کامل پر تو لئے ہوئے ) اور اس کے رسول ہیں.اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ
وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ - اے اللہ تو محمد کو اور ان کی امت کو ویسی ہی
101
Page 102
بزرگی عطا فرما (ان کو ویسے ہی انعام عطا فرما) جیسے تو نے ابراہیم اور اس کی امت کو عطا
فرمائی.دوسرے درود شریف میں صَل کی بجائے بارک کا لفظ ہے.جس کے معنی ہیں
برکت عطا فرما.تمہیں معلوم ہے پہلی دورکعتوں میں الحمد شریف کے بعد قرآن کریم کا کوئی
نصہ پڑھا جاتا ہے اور درود
شریف کے بعد بعض مسنون دعائیں کی جاتی ہیں اور نماز میں اپنی
زبان میں بھی دعائیں کی جاسکتی ہیں.اس جگہ میں قرآن کریم کی ایک مختصر سورة (سورۃ اخلاص) کا ترجمہ بھی لکھ دیتا
ہوں اور بعض مسنون دعاؤں کا بھی.قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ -
کہو اللہ ایک ہے.اور نہ بیٹا)
اللهُ الصَّمَدُ.اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں قائم ہے.کسی سہارے کا محتاج نہیں.لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ.نہ وہ جنا گیا اور نہ اس نے کسی کو جنا.( یعنی نہ اس کا باپ ہے
وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا اَحَدٌ.اور نہ اس کا کوئی ہمسر ہوسکتا ہے.رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ.اے میرے
رب ! مجھے نماز کی حقیقت پر قائم کر دے اور یہ میری دعا میری اولاد کے متعلق بھی قبول فرما.رَبَّنَا اغْفِرْلِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ.اے میرے رب
تو میرے گناہ بخش اور میری پردہ پوشی فرما اور میرے والدین اور تمام مومنین کے ساتھ بھی
بوقت حساب ایسا ہی سلوک کیجیو.رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ.اے
ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں
آگ ( سوزش قلب اور حسرت و غم وغیرہ) کے عذاب سے بچا.102
Page 103
اللهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ وَدَرْكِ الشَّقَاءِ وَسُوْءِ الْقَضَاءِ
وَشَمَاتَةِ الْاَعْدَاءِ.اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تیرے ساتھ اس بات سے کہ میں آزمائش
میں پھنس جاؤں یا بدبختی کو پہنچ جاؤں یا کوئی بری تقدیر میرے متعلق جاری ہو جائے یا میں ایسی
حالت کو پہنچ جاؤں کہ میرے دشمن مجھ پر ہنسیں.ایک رکعت کے دو سجدوں کے درمیان جو مختصر قعدہ ہوتا ہے اس میں یہ دُعا پڑھنی
چاہیے.رَبِّ اغْفِرْلِيْ وَارْحَمْنِي وَارْزُقْنِي وَاهْدِنِي وَاجْبُرْنِي وَعَافِنِيْ وَاعْفُ
عنی یعنی اے میرے رب میرے گناہ بخش اور ان سے چشم پوشی فرما اور مجھ پر رحم فرما اور
اپنے پاس سے مجھے رزق دے.اور میری ہدایت فرما اور میری خامیوں کو دور کر دے اور
کمیوں کو پورا کر دے اور مجھے اپنی پناہ میں رکھ لے اور مجھ سے در گذ رفرما.عشاء کی نماز میں وتروں میں تیسرے وتر کے قیام کے آخری حصہ میں سجدہ میں جانے
سے پہلے دعاء قنوت پڑھی جاتی ہے.وہ یہ ہے:.اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِي
عَلَيْكَ الْخَيْرَ.وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ.اَللّهُمَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ، وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ.وَنَرْجُوْا
رَحْمَتَكَ وَنَخْشَى عَذَابَكَ إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِق
یعنی اے اللہ ہم تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں اور تجھ سے بخشش چاہتے ہیں اور تجھ پر ایمان
لاتے ہیں اور تجھ پر سہارا رکھتے ہیں.اور تیری عمدہ ثناء کرتے ہیں اور تیری نعمتوں کا صحیح
استعمال کرتے ہیں.اور تیری نافرمانی نہیں کرتے اور ہم چھوڑ دیتے ہیں ان کو اور بیزار
ہو جاتے ہیں ان سے جو تیری نافرمانی کرتے ہیں.اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے
ہیں اور تیرے ہی سامنے جھکتے اور گرتے ہیں اور تیری طرف ہی دوڑتے اور بڑھتے ہیں اور
تیری رحمت کی امید رکھتے ہیں اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں کیونکہ جو لوگ تیری نعمتوں
کی ناقدری کرتے ہیں اور تیری ہدایت پر نہیں چلتے وہ آخر تیرے عذاب میں گرفتار ہوں
103
Page 104
گے.میں نے ایک امریکن عورت کی کتاب میں پڑھا کہ وہ سان فرانسسکو کے تباہ کن
زلزلہ کے بعد اتفاق سے اس شہر میں گئی اور اس کے دل پر اس بات کا بہت اثر پڑا کہ بڑی بڑی
عمارتوں کے لوہے کے پنجر ویسے کے ویسے کھڑے ہیں گو درمیان سے اینٹیں پتھر اور چونا
وغیرہ گر گئے ہیں.اس نے اس مثال کو پیش کر کے ثابت کرنا چاہا ہے کہ اگر انسان اپنے دن کو
چند حصوں میں تقسیم کر لے اور ہر حصہ کے آخر میں دوسرا حصہ شروع ہونے سے پہلے دعا
کرے تو اس کا دن ایک قسم کے روحانی پنجر میں تقسیم ہو جائے گا اور درمیان میں جو وقفے
ہونگے ان میں اگر دنیا داری کے امور کا کوئی اثر اس کی طبیعت پر پڑے جو اس کی روحانیت کو
نقصان پہنچانے والا ہو تو وہ اثر دعا کا وقت آجانے پر رک جائے گا اور اس کی روحانیت دعا
سے پھر تازہ ہو جائے گی اور وہ تازہ روحانیت کے ساتھ پھر اپنے کاروبار میں لگ جائے گا.گویا اگر کسی وقت اس کی روحانیت پر زلزلہ بھی آجائے تو یہ دعا کے آہنی ستون اس کی
روحانیت کی عمارت کے ڈھانچے کو قائم رکھیں گے اور جو مینٹیں یا پھر درمیان سے گر گئے ہوں
وہ تھوڑی سی محنت سے پھر اپنی اپنی جگہ لگائے جا سکتے ہیں.یہ پڑھ کر مجھے خیال ہوا کہ اسلام
میں تو پہلے ہی سے یہ انتظام ہے کہ انسان مقررہ اوقات میں تھوڑے تھوڑے وقفہ سے اپنی
روحانیت کو تازہ کرتا رہے تا اس کی زندگی کی اصل بنیاد روحانیت پر ہو اور اگر دوسرے اثرات
اس کی زندگی پر پڑیں تو ان کا تھوڑے تھوڑے وقفہ سے ازالہ ہوتارہے.ذکر الہی
پھر ذکر الہی ہے اور یہ زیادہ تر انسان کے قلب کے ساتھ تعلق رکھتا ہے.مومن کے
دل کی یہ کیفیت چاہئے کہ اگر اپنے فرائض کے لحاظ سے اسے دنیا کی طرف متوجہ بھی ہونا
پڑے تو اس کا دل بھاگ کر اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف جانا چاہیئے گویا ایک مسلسل پیاس اور
104
Page 105
تڑپ ہے جسے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ بجھانا اور ٹھنڈا کرنا چاہتا ہے.اور جیسا میں کہ چکا ہوں دعا کا اصل وقت تو نماز ہی ہے.کیونکہ نماز تمام ترحم اور تسبیح
اور دعا ہے اور نماز کا وقت خصوصیت سے قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے لیکن نماز کے اوقات
سے باہر بھی انسان کو جو کہیں موقعہ ملے دعا کی طرف رجوع کرنا چاہیئے.حضرت مسیح موعود
علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار فرمایا ہے کہ ایک مومن کے لئے کیا یہ کم خوشی اور اطمینان کا
مقام ہے کہ اس کا خدا ہر بات پر قادر ہے اور دعاؤں کوسنتا اور قبول کرتا ہے.دعا کی قبولیت
کے لئے بہت سے لوازم ہیں لیکن سب سے ضروری شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر
ایمان ہو اور اس وثوق سے دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے اور اس کے
سامنے کوئی بات انہونی نہیں.گو یہ بھی یا درکھنا چاہئے کہ وہ آقا اور مالک ہے اور گو وہ نہایت
شفیق اور رحیم ہے اور دعاؤں کو قبول کرتا ہے لیکن وہ انسان پر حاکم ہے.يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ
اور پھر انسان
کو ہمیشہ یہ علم بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک دعا جو وہ کر رہا ہے اس کا قبول ہو جانا اس کے
لئے مفید ہے یا مضر.اس لئے اللہ تعالیٰ جو کہ عالم الغیب ہے اور ہر بات کے انجام کو جانتا
ہے بعض دفعہ اس لئے دعا کو قبول نہیں کرتا کہ اس کی رحمت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ دعا قبول نہ
کی جائے کیونکہ اس کی قبولیت دعا کر نیو الے کے حق میں مضر ثابت ہوگی.لیکن وہ کسی کے
اخلاص کو ضائع نہیں کرتا اور اگر دعا نیک نیتی اور اخلاص سے کی جائے تو اس کا اجر انسان کو
ضرور ملتا ہے خواہ کسی رنگ میں ہو.اس لئے انسان کو دعا کرنے میں اپنے رب کی آزمائش
نہیں کرنی چاہئے اور نہ اپنے دعوی عشق و وفا کومشروط کرنا چاہئے.روزه
نماز کے پہلو بہ پہلو ایک اور اہم عبادت روزہ ہے.رمضان کے روزے تو ہر مسلمان
پر فرض ہی ہیں سوا ایسی حالتوں کے جو مستثنی کی گئی ہیں.اور اس کے علاوہ نفلی روزے ہیں.105
Page 106
روزے کے دوران میں جیسا تمہیں علم ہے
کھانا پینا اور میاں بیوی کے تعلقات منع ہیں.اور یہ
ہدایت ہے کہ روزہ کے دوران میں اور رمضان کے مہینے میں تمام مہینہ انسان ذکر الہی کی
طرف زیادہ توجہ کرے اور قرآن کریم کا زیادہ مطالعہ کرے اور اگر باقی ایام میں تہجد کے نفل
نہ بھی پڑھتا ہو تو رمضان میں ضرور پڑھے اور عام دنیاوی مشاغل میں جس قدر ممکن ہو تخفیف
کر دے اور صدقہ و خیرات کی طرف عام اوقات کی نسبت زیادہ مائل رہے اور لڑائی جھگڑے
سے اجتناب کرے.رمضان کے بہت سے فضائل ہیں جن کا بیان بہت تفصیل چاہتا ہے لیکن میں اپنے
ذوق کے مطابق بعض پہلو مختصر طور پر بیان کئے دیتا ہوں.انسان کی زندگی کا قیام جسمانی طور
پر کھانے پینے پر منحصر ہے اور نسل انسانی کا بقا میاں بیوی کے تعلقات پر منحصر ہے.روزہ کے
دوران میں انسان ان دونوں سے اجتناب کرتا ہے.گویا اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک قسم کی
شہادت پیش کرتا ہے کہ میں تیری رضا کی خاطر ان اسباب کو جن پر میری زندگی اور میری نسل
کے بقا کا مدار ہے ترک کرتا ہوں.اور گو یہ ترک کرنا عارضی ہوتا ہے( کیونکہ روزہ سے
اللہ تعالیٰ کی مراد انسان کی زندگی یا اس کی نسل کو ختم کر دینا نہیں بلکہ ان میں اصلاح اور برکت
اور ترقی مقصود ہے ) لیکن اس عارضی قربانی کو انسان بطور ایک عہد کے پیش کرتا ہے کہ اگر
تیرے رستہ میں ضرورت پیش آجائے تو میں کلی طور پر اپنی زندگی اور اپنی نسل قربان کرنے
کے لئے تیار ہوں.یہ ایک بہت بڑا عہد اور بہت بڑی ذمہ داری ہے.اگر انسان اخلاص
کے ساتھ یہ عہد کرے اور اس کے پورا کرنے کے لئے تیار رہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے
بہت سی برکات اور انعامات کا مورد ٹھہرتا ہے.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارا بھوکا اور پیاسا رہنا
روزے کی غرض نہیں ہے بلکہ تمہارا تقویٰ اصل مقصود ہے.اور دیگر فوائد روزے کے یہ ہیں کہ انسان کو جسمانی آرام کی قربانی کی مشق ہو جاتی
ہے اور وہ بھوک اور پیاس کی برداشت کرنے کا عادی ہو جاتا ہے.اور روزہ امیر اور غریب
کے درمیان ایک مساوات کا احساس پیدا کر دیتا ہے اور امیروں کو بھوک کا احساس پیدا کر کے
106
Page 107
غرباء کی ضروریات کی طرف توجہ دلاتا ہے اور ان کے دلوں میں ہمدردی کا جذبہ پیدا کر دیتا
ہے.ان کو عملاً یہ بتا دیتا ہے کہ بھوک اور پیاس کی شدت کے وقت انسان کی کیا حالت ہوتی
ہے.رمضان انسان کی روحانی ترقی کا ایک نہایت ہی مؤثر ذریعہ اور عمدہ موقعہ ہے.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور عبادتوں کے تو اور اجر ہیں لیکن روزہ کا اجر میں خود ہی ہوں اس سے
روزہ کی اہمیت اور اس کی برکات کا اندازہ ہو سکتا ہے.حج
پھر ایک عبادت حج ہے جو ہر بالغ اور عاقل مسلمان پر جو اس کی استطاعت رکھتا ہو
اور استطاعت میں یہ بھی شامل ہے کہ علاوہ مالی استطاعت کے سفر اور دوران حج میں امن
بھی میسر ہو ) فرض ہے.حج سے مراد یہ ہے کہ مقررہ ایام میں حج کی نیت رکھنے والا مسلمان
مکہ مکرمہ کا سفر اختیار کرے اور مقررہ مقامات پر حج کے مناسک پورے کرے.ان مناسک
کی تفصیل بیان کرنے کی یہاں ضرورت نہیں صرف اس امر کی طرف توجہ دلانا درکار ہے کہ
مکہ کا شہر اور وادی زمانہ قدیم سے مہبط انوار الہی چلے آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین
کو برکت اور ہدایت کا سر چشمہ قرار دیا ہے.حضرت ابراہیم اور حضرت اسمعیل کے ہاتھوں
سے یہاں بیت اللہ تعمیر ہوا.پھر افضل الرسل اور خاتم النبین ﷺ یہاں پیدا ہوئے اور
یہیں پرورش پائی اور یہیں جوان ہوئے اور یہیں منصب رسالت آپ کو عطا کیا گیا.اور
قرآن کریم کا نزول بھی یہیں سے شروع ہوا.اور دنیا کی ہدایت آپ کے سپرد کی گئی اور یہیں
سے وہ روحانی چشمہ جاری ہوا جو اصل زندگی کا چشمہ ہے.جو شخص اس سے سیراب ہوتا ہے وہ
ہمیشہ کی زندگی پاتا ہے.جو اس سے محروم رہتا ہے وہ حقیقی زندگی سے محروم رہتا ہے.اسلام نے یہ نظام قائم کیا ہے کہ ہر محلہ کے مسلمان دن رات میں پانچ دفعہ اپنے محلہ
107
Page 108
کی مسجد میں جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شامل ہوں اور جمعہ کے دن اس سے وسیع رقبہ
کے مسلمان جمعہ کی نماز کے لئے اکھٹے ہوں اور اس موقعہ پر امام نماز سے پہلے خطبہ بھی پڑھے
جس میں اپنے مقتدیوں
کو اسلامی تعلیم کے کسی پہلو کی طرف توجہ دلائے خواہ وہ پہلو دینی ہو یا
اخلاقی یا معاشرتی یا تمدنی.اور پھر سال میں دو بار عیدین کے موقعہ پر تمام شہر کے یا ایک علاقہ
کے مسلمان ایک جگہ جمع ہوں اور عید کی نماز کھٹے ایک جگہ ادا کریں اور خطبہ سے بھی مستفید
ہوں.اور پھر حج کے موقع پر اکناف عالم سے مسلمان مکہ معظمہ میں جمع ہوں اور مناسک حج
بجالائیں اور آپس میں اسلامی اخوت کے رشتہ کو تازہ کریں اور مسلمانوں کی بہبودی اور ترقی
کی تجاویز پر غور کریں.مناسک حج کے بجالانے میں ایک احساس جو ہر حاجی کے دل میں ولولہ پیدا کر کے
بار بار رفت سے اس کی آنکھوں کو پر آب کر دیتا ہے یہ ہے کہ یہ وہ سرزمین ہے جس میں
رسول اللہ ﷺ نے اپنی حیات مبارکہ طیبہ کا اکثر حصہ گزارا اور ہر مقام حضور ﷺ کی
حیات مبارکہ کے واقعات کو آنکھوں کے سامنے لاتا ہے.اور جو قربانیاں حضور ﷺ نے
اسلام کی خاطر کیں ان کی یاد تازہ کرتا ہے.اسلام کس حالت میں شروع ہوا اور کن تکالیف
اور مصائب سے گذرا اور کس طرح اللہ تعالیٰ کے وعدے پورے ہوئے اور باوجود دشمنوں کی
طاقت اور ان کے جتھہ کے اور مسلمانوں کی قلیل تعداد اور ظاہری سامانوں کی کمی بلکہ فقدان
کے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ عطا کیا، یہ سب نقشہ بار بار آنکھوں کے آگے پھرتا ہے.اور ایک
مومن کے ایمان کو تازہ کرتا ہے اور ساتھ ہی مسلمانوں کی موجودہ حالت دیکھ کر دل میں درد اور
حسرت پیدا ہوتی ہے اور اسلام کے احیاء اور دوبارہ غلبہ کے لئے دل سے دعائیں نکلتی ہیں.الله
اخلاق
اب میں اسلامی تعلیم کے اس حصہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں جو انسانی اخلاق کے
108
Page 109
ساتھ تعلق رکھتا ہے.اور اس کی بعض خصوصیات کو تمہارے ذہن نشین کرنے کی کوشش کرتا
ہوں.یہ حصہ اسلامی تعلیم کا ایک نہایت ضروری حصہ ہے.کیونکہ اس کی طرف پہلے زمانوں
میں بہت کم توجہ کی گئی ہے.اور ساتھ ہی اس وجہ سے بھی یہ ضروری ہے کہ باقی مذاہب میں
اس کے مقابل کوئی ہدایات نہیں پائی جاتیں.استقدر تو ہر شخص کو تسلیم ہے کہ ہر مذہب نے یہ
تعلیم دی ہے کہ انسان کے اخلاق اچھے ہونے چاہئیں.اور فی الجملہ ہر مذہب نے اپنے
پیرؤوں سے کہا ہے کہ سچ بولیں، کسی کا حق نہ ماریں قتل و غارت نہ کریں وغیرہ لیکن نہ تو کسی
نے فلسفہ اخلاق پر بحث کی ہے نہ اخلاق کے درجے مقرر کئے ہیں اور نہ اخلاقی تربیت اور
ترقی کے طریق سکھائے ہیں.یہ خصوصیت صرف اسلام کو حاصل ہے کہ اسلام نے ان امور
کی طرف توجہ کی ہے اور اخلاقی تربیت اور ترقی کی راہیں بتا کر اس کو سہل الحصول کر دیا
ہے.ان امور پر مفصل بحث حضرت
مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب اسلامی اصول کی
فلاسفی میں فرمائی گئی ہے اور حضرت خلیفتہ اسیح الثانی کی کتاب احمدیت یعنی حقیقی اسلام میں
بھی ان امور کی وضاحت کی گئی ہے.یہ دونوں کتابیں گہرے مطالعہ اور توجہ کے لائق ہیں اور
تمہیں ان کا ضرور مطالعہ کرنا چاہئے.فلسفه اخلاق
اچھے اور برے
عمل کی کیا تعریف ہے؟ اس ضمن میں جانا چاہئے کہ اسلام نے خیال کو
بھی عمل میں شامل کیا ہے.اور خیالات اور ظاہری اعمال دونوں کی اصلاح کی تعلیم دی ہے
کیونکہ خیال در اصل منبع ہے عمل کا.لیکن فی الحال ظاہری اعمال کو ہی مد نظر رکھتے ہوئے پہلی
بات
جو تمہیں ذہن نشین کر لینی چاہئے وہ یہ ہے
کہ کوئی فعل محض بحیثیت ایک فعل کے اچھا یا برا
نہیں ہوتا بلکہ فاعل کی نیت اور فعل کے محل کے لحاظ سے اچھا یا برا ہو جاتا ہے.یہ تو ظاہر ہے
که تمام اعمال چند بالا رادہ حرکات کی صورت میں انسان سے ظاہر ہوتے ہیں اور یہ حرکات
109
Page 110
اپنے اندر نہ بری ہیں نہ اچھی.ان
کا برا یا اچھا ہونا حرکات کے فاعل کی نیت اور ان حرکات
کے محل پر موقوف ہے.اور اس نیت اور محل کے لحاظ سے ہر انسانی فعل یا تو تقویٰ کا رنگ
اختیار کر لیتا ہے یا ظلم کا.اسی لئے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ
بالنيات.یعنی اعمال کی خیر یا شر عامل کی نیت پر منحصر ہے.اس طرح تقوی اور ظلم کی تعریف
یہ ہے کہ ہر فعل جو نیک نیت کے ساتھ اپنے محل اور دائرہ کے اندر کیا جائے وہ تقویٰ ہے اور ہر
فعل جو خلاف محل یا نیت فاسد سے کیا جائے وہ ظلم ہے.مثلاً ایک انسان کسی دوسرے انسان
کو قتل کر ڈالتا ہے تو محض قتل نہ اچھا ہے نہ برا.نیت اور محل اس کو اچھایا برا بنا دیتے ہیں.ایک
شخص دیکھتا ہے کہ دوسرا شخص ایک با عصمت عورت پر اس کی عصمت دری کی نیت سے حملہ
آور ہورہا ہے اور اس کمز ور عورت کو اس وحشی انسان کے حملہ سے بچانے کا اور کوئی طریق نہیں
سوا اس کے کہ اس پر فور أحملہ کر دیا جائے اور یہ اس پر حملہ کر دیتا ہے اور وہ شخص اس کا مقابلہ
کرتا ہے لیکن مقابلہ میں اپنی جان کھو دیتا ہے.اب اگر چہ یہ فعل ایک انسان کی جان لینے کا
ہے لیکن اس نیت کی وجہ سے جس سے یہ کیا گیا اور اس محل کے سبب سے جس پر یہ صادر ہوا یہ
ایک اچھا فعل ہے.اسی طرح ایک سپاہی جب جنگ میں لڑتا ہے اور دشمن کے سپاہیوں کو قتل
کرتا ہے تو اس کا فعل مستحسن ہے.ایک ڈاکٹر ایک مریض کا نیک نیتی سے آپریشن کرتا ہے اور
ہر ممکن کوشش اس کے بچانے کی کرتا ہے لیکن باوجود اس کوشش کے وہ مریض مرجاتا ہے تو
ڈاکٹر کا فعل قابل تحسین ہے.لیکن فرض کرو وہ ڈاکٹر اپنے علم اور تجربہ کے لحاظ سے جانتا ہے
کہ مریض کی حالت یا مرض کی نوعیت ایسی ہے کہ اس حالت میں آپریشن کرنا مریض کو
نقصان پہنچانے کا موجب ہوگا اور اس کی صحت پر مضر اثر ڈالے گا اور ممکن ہے کہ مریض اس
کے نتیجہ میں جانبر نہ ہو سکے اور پھر بھی وہ آپریشن کرتا ہے اور اس کی نیت مریض کو فائدہ پہنچانا
نہیں بلکہ نقصان پہنچانا ہے اور آپریشن کے نتیجہ میں مریض مرجاتا ہے یا باوجود اپریشن کے
صحتیاب ہو جاتا ہے دونوں صورتوں میں ڈاکٹر کا فعل ظالمانہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا
110
Page 111
ایک ابتدائی اسلامی جنگ کا واقعہ ہے کہ ایک شخص مسلمانوں کی طرف سے بڑے
جوش سے لڑ رہا تھا اور بہادری کے جوہر دکھا رہا تھا اور دشمن کے بہت سے آدمیوں کو اس نے
مارا اور زخمی کیا.لیکن رسول اللہ ﷺ نے اسے دیکھ کر اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ یہ شخص
جہنمی ہے.ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ میں نے جب رسول اللہ ﷺ کا یہ قول سنا تو
میں اس شخص کے پیچھے ہولیا تا میں اس کے انجام کو دیکھوں.وہ شخص پہلے تو بہت جوش سے لڑتا
رہا اور دشمن پر اس نے خوب وار کئے لیکن پھر وہ زخمی ہو کر لڑائی سے ایک طرف ہٹ گیا اور اس
نے اپنی تلوار قبضہ کے بل زمین پر کھڑی کی اور اس کی نوک سے اپنا سینہ لگا کر اور اس پر اپنا
بوجھ ڈال کر خود کشی کر لی اور اس طرح اپنے جہنمی ہونے پر مہر ثبت کر دی اس شخص سے متعلق
معلوم ہوا کہ وہ جنگ میں خدا تعالیٰ کی رضا جوئی کے لئے شامل نہیں ہوا تھا بلکہ اسے مخالف
لشکر کے بعض آدمیوں سے دشمنی اور عناد تھا اور اس نے اس موقع کو بدلہ لینے کے لئے غنیمت
جانا اور مسلمانوں کی طرف سے لڑائی میں شامل ہو گیا اور ان لوگوں کو قتل یا زخمی کر دیا جن کے
ساتھ اس کی دشمنی تھی.اب کیا تو اس نے بھی وہی جو مسلمان کر رہے تھے اور بظاہر اس نے
مسلمانوں کی بہت مدد کی اور انہیں تقویت پہنچائی لیکن وہ جو خدا کی رضا کے لئے لڑ رہے تھے
انہوں نے تو جنت حاصل کر لی اور اس شخص نے خود کشی کر کے جہنم کی راہ لی.اسی طرح ایک جنگ کے موقعہ پر رسول اللہ ﷺ نے اپنے ایک صحابی کو دیکھا کہ
با وجود کمزور اور نحیف ہونے کے دشمن کو دکھانے کے لئے چھاتی نکال کر اور اکٹر اکٹر کر چل
رہے ہیں.آپ نے فرمایا اکڑ اکٹر کر انا اللہ تعالی کو پسند نہیں لیکن اس وقت مخالفین اسلام
کے مقابلہ پر اس شخص کا اکڑ اکڑ کر چلنا اللہ تعالی کو پسند آیا.گویا وہی فعل جو عام طور پر ناپسندیدہ
تھا، نیت اور محل کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا باعث ہو گیا.اسی طرح مرد و عورت کے تعلقات ہیں.اپنی ذات میں یہ تعلق ایک قدرتی خواہش کا
پورا کرنا ہے اور نہ اچھا ہے نہ برا ہے.اگر اپنے محل پر ہے تو اچھا ہے اور اپنے محل پر نہیں تو برا
ہے.مثلاً ایک شادی شدہ مرد اور عورت آپس میں محبت اور شفقت سے رہتے ہیں اور ایک
111
Page 112
دوسرے کا لباس ہیں یعنی وہ آپس کی محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود کو قائم رکھتے
ہیں اور ایک دوسرے سے حسن معاشرت کے ساتھ پیش آتے ہیں اور ان کے باہمی تعلقات
کی بناء تقویٰ پر ہے اور وہ نیک اولاد کی خواہش رکھتے ہیں.اس نیت سے کہ ایسی اولاد
اللہ تعالیٰ کی خادم ہوگی اور دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو قائم کرنے والی ہوگی تو ان کے تعلقات
موجب ثواب اور برکت ہیں.لیکن اگر ایک مرد و عورت کا باہمی تعلق محض نفسانیت کی بناء پر
ہے تو اگر تو وہ میاں بیوی نہیں تو یہ تعلق بوجہ غیر محل پر ہونے کے ظلم ہے.اور اگر وہ میاں بیوی
بھی ہیں تو بھی گو ظاہری قانون اور فقہ کی زد سے تو بے شک وہ قابل گرفت نہیں لیکن حقیقی
اخلاق کے لحاظ سے ان کا تعلق مستحسن نہیں سمجھا جائے گا کیونکہ وہ نیک نیتی پر مبنی نہیں ہے اور
ایسا تعلق بہر حال مخرب اخلاق ہوگا.اسی لئے کہا گیا ہے کہ فتویٰ اور شے ہے اور تقویٰ اور
شے.فتویٰ تو صرف ظاہر پر چلتا ہے جو فعل قانون کی حد کے اندر رہتا ہے وہ فتویٰ کی رو سے
جائز ہے یعنی قابل گرفت نہیں.اور جو فعل قانون کی حد سے باہر ہے وہ ناجائز ہے اور
قابل گرفت ہے.لیکن یہ ایک ادنیٰ درجہ اخلاق کا ہے اور تقویٰ کا مقام اس سے بڑھ کر ہے.کیونکہ وہ نیت اور دل سے تعلق رکھتا ہے اور دراصل اعلیٰ اخلاق تقویٰ کے مقام پر پہنچ کر ہی
حاصل ہوتے ہیں.جو فعل برمحل ہے وہ جائز ہے لیکن اگر حسن نیت بھی اس کے ساتھ شامل
ہے تو وہ اعلیٰ اخلاقی فعل بن جائے گا اور تقومی کہلائے گا.دین کی غرض محض جرم سے بچانا ہی
نہیں بلکہ گناہ سے بچانا بھی ہے اور پھر اس سے بڑھ کر تقی اور اعلیٰ اخلاق کا انسان بنانا ہے.قانون اور مذہب میں بڑا فرق یہ ہے کہ قانون صرف اعمال کی اصلاح کو مد نظر رکھتا ہے.یعنی
اس کا اطلاق محض ظاہری افعال پر ہوتا ہے اور اکثر اوقات فعل کے صادر ہو چکنے کے بعد
بصورت سزا ہوتا ہے.مگر دین یا مذہب اخلاق کی درستگی کو مقصد قرار دیتا ہے اور اس کی حکومت
قلب اور نیت اور ارادہ پر ہوتی ہے تا کہ افعال کے منبع کو صاف کیا جائے اور وہاں سے جو فعل
صادر ہونے کی حرکت ہو وہ نیک ہو اور اس کے نتیجہ میں اعمال میں خود بخو داصلاح ہو جائے.اسی لئے مذہب کی اصطلاح میں خیال اور ارادہ کو بھی قابل گرفت یا قابل انعام فعل قرار دیا
112
Page 113
گیا ہے اور اخلاقی افعال کی بناءنیت پر رکھی گئی ہے اور محض محل پر ہی اکتفا نہیں کیا گیا.اسی طرح نیت کے لحاظ سے بعض اعمال محض اعلی نیت پر مبنی ہونے کی وجہ سے زیادہ
انعام کے مستحق بن جاتے ہیں.اور عام نیت کے لحاظ سے وہ ویسے اعلی نہیں رہتے.اور اسی
لحاظ سے ان کا اثر انسان کی اخلاقی اور روحانی ترقی پر پڑتا ہے.ایک صحابی نے اپنا مکان مسجد
کے قریب بنایا اور رسول اللہ ﷺ کو دعوت دی کہ حضور اس مکان میں برکت کے لئے
تشریف لائیں.چنانچہ حضور تشریف لے گئے.ایک دریچہ کو دیکھ کر حضور نے دریافت فرمایا
یہ کس غرض کے لئے رکھا ہے؟ صحابی نے عرض کیا کہ حضور ہوا اور روشنی کی خاطر.آپ نے
فرمایا اگر تم یہ نیت کر لیتے کہ اس کھڑکی سے اذان کی آواز زیادہ آسانی سے سنی جائے گی تو ہوا
اور روشنی تو آتے ہی رہتے اور ساتھ ہی تمہیں تمہاری نیت کا ثواب بھی مل جاتا.اسی طرح
حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر انسان چاہے تو محض نیت کے نیک
کر لینے سے اپنے ہر فعل کو ثواب اور برکت کا موجب بنا سکتا ہے.مثلاً ہر شخص کھاتا پیتا ہے
اور کھانے اور پینے سے لذت حاصل کرتا ہے اور عام انسانوں کی غرض کھانے پینے سے اس
سے زیادہ نہیں ہوتی کہ بھوک اور پیاس کے تقاضوں کو پورا کریں اور زبان کے ذائقہ سے
لطف اٹھا ئیں اور بدن میں طاقت آئے.لیکن اگر ایک مومن یہ نیت کر لے کہ میں اس لئے
کھاتا پیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے یہ سب اشیاء تمہاری خدمت کے لئے
پیدا کی ہیں تم حلال کی روزی کماؤ اور کھاؤ تا اپنی زندگی اور طاقتوں
کو قائم رکھو اور انہیں میری
رضا جوئی میں صرف کرو.اور اگر اس کی نیت اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی فرمانبرادری اور اس کی
رضا جوئی ہے تو لطف تو وہ بھی ویسے ہی اٹھائے گا جیسے دوسرے لوگ بلکہ ان سے بڑھ کر کیونکہ
وہ معرفت کے ساتھ کھائے گا لیکن ساتھ ہی وہ ثواب بھی حاصل کرے گا.یعنی یہ کھانا اور پینا
اس کی روحانی ترقی میں مرد اور اللہ تعالیٰ کے قرب کے حصول کا موجب ہوگا.اسی طرح ایک مومن ہر قدرتی تقاضے کو پورا کرتے ہوئے اگر نیت اعلیٰ رکھے تو اپنی
زندگی کے ہر فعل سے روحانی فوائد حاصل کر سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے میں
113
Page 114
سرعت سے ترقی کر سکتا ہے.کھانا پینا ، لباس پہننا اور روزی کمانا، مکان بنانا، ورزش کرنا،
مطالعہ کرنا، بیاہ شادی ، گھر کی معاشرت، اولاد حاصل کرنا، اولاد کی تربیت کرنا سب اس
طریق سے اعلی اخلاقی اور روحانی افعال بن سکتے ہیں.مثلاً ہر شخص بیوی بچوں کی ضرورت
مہیا کرتا ہے.محنت کرتا ہے، کما کر لاتا ہے اور بیوی بچوں کا پیٹ پالتا اور ان کی ضروریات کا
انتظام کرتا ہے.اب اگر تمام وقت اس کی نیت یہ ہو کہ میں ایسا اس لئے کرتا ہوں اور مجھے ایسا
اسلئے کرنا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم بیوی بچوں کی ضروریات کو پورا کرو تو وہ تمام وقت
گو یا اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی میں لگا ہوا ہے اور اس کی یہ تمام محنت تقویٰ کی ذیل میں آجاتی ہے
اور اس کے لئے ترقی اور ثواب کا موجب ہے.اور اگر وہ ہر کام میں ایسی نیت رکھ لے گا تو
اس کی زندگی کی خود بخود اصلاح ہوتی چلی جائے گی اور اس کا کوئی کام تقویٰ کے خلاف نہیں
ہوگا.اگر روزی کمانے میں ایک شخص کی نیت وہ ہوگی جو میں نے بیان کی ہے تو پھر یہ ممکن نہیں
کہ وہ اپنی روزی ناجائز وسائل سے حاصل کرے.مثلاً کسی کا حق مارے یا کسی کو فریب دے
یا رشوت لے.کیونکہ جب اس کی نیت اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری اور اس کی رضا جوئی ہے تو وہ
روزی ان ذرائع سے ہی حاصل کرے گا جو اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں پسندیدہ ہیں.اسی طرح اگر ایک شخص ملازم ہو تو اس کو اپنے فرائض کو کمال دیانتداری اور تندہی
سے ادا کرنا چاہئے.اس لئے نہیں کہ اس کا آقایا افسر خوش ہو کر اسے انعام دے گا ، اسے ترقی
ملے گی بلکہ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوگا کیونکہ اس کی رضا یہ ہے کہ ہر ملازم اپنے
فرائض تندہی اور دیانت سے بجا لائے اور ہر آقا اور افسر اپنے ملازموں اور ماتحتوں سے
شفقت اور نرمی کا سلوک کرے.اگر اس طور پر ہر شخص اپنی نیت کی اصلاح کرلے تو اعمال کا تمام معیار ہی بدل جاتا
ہے اور انسانی زندگی بالکل امن اور دوستی کی زندگی بن جاتی ہے.114
Page 115
اخلاق کے مدارج
پھر اسلام نے اخلاق کے درجے مقرر کر دئے ہیں جن کو مد نظر رکھنے سے انسان
آسانی سے اپنے اعمال اور اخلاق کی پڑتال اور اصلاح کر سکتا ہے.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ
اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْى
یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں عدل اور احسان اور ایتائے ذی القربی کا حکم دیتا ہے.اور فحشاء
اور منکر اور بنی سے منع کرتا ہے.اس حد بندی کے لحاظ سے سب سے نچلا درجہ برے اعمال کا بنغی ہے.اس سے اوپر
منکر اور اس سے اوپر فحشاء اور سب سے ادنیٰ درجہ نیکی کا عدل ہے.اور اس سے بڑھ کر
احسان اور اس سے بڑھ کے ایتائے ذی القربی.بعی سے مراد ایسے اعمال ہیں جن سے دوسرے انسانوں کو دکھ اور ایذاء پہنچتی ہے اور
جوان کے حقوق کو پامال کرتے ہیں.مثلا کسی کو گالی دینا یا کسی پر حملہ کرنا یا کسی کا مال چرا لینا یا
کسی کو فریب دینا.غرض ہر وہ فعل جو کسی دوسرے انسان کے لئے دکھ اور تکلیف کا موجب
ہوتا ہے اور اس کے حقوق میں دخل انداز ہوتا ہے وہ بنی ہے.منکر سے مراد ایسے افعال ہیں جنہیں دوسرے لوگ نا پسند کرتے ہیں.مثلاً عام
بدزبانی یا بے حیائی یعنی ناپسندیدہ اور مکروہ افعال.ایک شخص رہگزر پر یا اس کے قریب
پیشاب یا پاخانہ کے لئے بیٹھ جاتا ہے یا بھری مجلس میں صاف ستھرے فرش پر تھوک دیتا
ہے.یا کوئی ایسا فعل یا ایسی حرکت کرتا ہے جو دوسروں پر گراں گزرتی ہے اور ان کی ذہنی
تکلیف کا باعث ہوتی ہے.فحشاء سے مراد ایسے افعال ہیں جن کا ظاہر میں دوسروں پر کوئی اثر نہیں پڑتا لیکن اگر
ا سورة النحل - آیت 91
115
Page 116
ان کو روکا نہ جائے تو ان سے برے افعال صادر ہونے کا اندیشہ ہے.اور اس لحاظ سے یہ
افعال خود انسان کے لئے اخلاقی اور روحانی لحاظ سے مضر ہیں.اس کے ماتحت زیادہ تر
گندے اور مکروہ اور ناپسندیدہ خیالات اور تصورات آتے ہیں.جیسا میں نے ذکر کیا ہے
اسلام نے خیالات اور تصورات اور ارادوں کو بھی اخلاقی افعال میں شامل کیا ہے کیونکہ یہ
ظاہری اعمال کا منبع ہوتے ہیں.اب ہر انسان اس معیار کے لحاظ سے اپنے اعمال اور اخلاق کی پڑتال کر سکتا ہے اور
ان کی اصلاح کی طرف متوجہ ہو سکتا ہے.اور پھر اس اصلاح اور ترقی کی رفتار کا اندازہ کر سکتا
ہے.یہ لازم نہیں ہے کہ انسان پہلے یہ کوشش کرے کہ بنی کے درجہ سے پورے طور پر نکل
آئے اور پھر منکر کی طرف متوجہ ہو.یا پہلے منکر کو پورے طور پر ترک کر دے اور پھر فحشاء کی
طرف توجہ کرے.وہ ایک ہی وقت میں تمام درجوں کی اصلاح شروع کر سکتا ہے اور اس
طرح ہر درجہ کی اصلاح دوسرے درجوں کی اصلاح میں ممد ہو سکتی ہے.اور اسی طرح جب
انسان پڑتال کرتا چلا جائے گا تو وہ معلوم کر لے گا کہ کن بدیوں کی طرف اس کی طبیعت
خصوصیت سے راغب ہے.اور پھر وہ خالص طور پر ان بدیوں کی اصلاح کی طرف متوجہ
ہوسکتا ہے.بدیوں کا ترک کرنا گو اخلاقی اصلاح اور ترقی کے لئے ایک ضروری اور لازم مرحلہ
ہے لیکن اگر انسان تمام بدیوں کو ترک کر دے تو بھی وہ ایک اعلیٰ اخلاق کا انسان نہیں کہلا سکتا
کیونکہ اعلیٰ اخلاق سے مراد یہ ہے کہ وہ نیک اخلاق کو بھی حاصل کرے.کوئی انسان محض اس
بات پر مطمئن نہیں ہوسکتا کہ وہ چوری نہیں کرتا قتل نہیں کرتا ، زنا نہیں کرتا ، مکر وفریب سے
لوگوں کا مال نہیں لوشا ، بے حیائی کا مرتکب نہیں ہوتا ، گندے خیالات اور منصوبوں اور ارادوں
کو اپنے دماغ میں جگہ نہیں دیتا.اس سے اس کو اتنا اطمینان تو ہو سکتا ہے کہ اس نے برائی سے
چھٹکارا حاصل کر لیا لیکن یہ اطمینان نہیں ہو سکتا کہ اس نے کوئی نیکی حاصل کر لی ہے یا کوئی بلند
اخلاق حاصل کر لیا ہے.ابھی گویا اس نے اخلاقی اصلاح اور ترقی کی صرف ایک ہی منزل
116
Page 117
طے کی ہے.اور دوسری اور زیادہ اہم منزل طے کرنی اس کے لئے باقی ہے اور وہ کسب خیر کی
منزل ہے.یعنی عدل و احسان اور ایتائے ذی القربی کی منزل یا منازل.عدل سے مراد یہ ہے کہ انسان نیک سلوک کے بدلہ میں کم سے کم برابری کا نیک
سلوک لوگوں کے ساتھ کرے.یعنی اس کے اخلاق کی اس قدر تربیت اور اصلاح ہو چکی ہو
کہ وہ کم سے کم برابری کے سلوک کا عادی ہو جائے اور برے سلوک کے مقابلہ میں اس کی
نسبت بڑھ کر سختی نہ کرے.احسان سے مراد یہ ہے کہ ایک انسان کے اخلاق اس قدر ترقی یافتہ ہو جائیں کہ وہ ہر
نیک سلوک کے مقابلہ میں اس سے بڑھ کر سلوک کرے اور برے سلوک کی مدافعت نیک
سلوک کے ساتھ کرے.جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تم برے سلوک کا بدلہ نیک سلوک سے
دو.اس طرح تم دیکھو گے تمہارا دشمن تمہارا نہایت گہرا دوست بن جائے گا.اور ایتائے ذی القربی سے مراد یہ ہے کہ انسان سے نیکی کسی بدلہ کہ خیال سے صادر نہ
ہو بلکہ اس کی طینت کا جزو بن جائے.اور خواہ اور لوگ اس کے ساتھ کیسا ہی سلوک کریں اس
کی طرف سے ہمیشہ نیک افعال ہی صادر ہوں.یعنی نیک اعمال اس سے اس طور پر صادر
ہوں جیسے ایک انسان قدرتی جذبہ کے ماتحت اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں سے سلوک کرتا
ہے.اخلاق کے اس درجہ کی مثال کسی نے یوں بھی دی ہے کہ شہد کے چھتہ کوکوئی شخص پتھر بھی
مارے تو اس سے شہد ہی گرتا ہے کیونکہ اس کے اندر شہد ہی شہد ہے.اس مرحلہ پر پہنچ کر انسان
کی سرشت میں نیکی ہی نیکی سرایت کر جاتی ہے اور بدی کا کوئی پہلو باقی نہیں رہتا.غور کرو کہ اسلام نے اخلاقی ترقی کے اصول کیسے عمدہ اور دلچسپ طور پر وضع کئے
ہیں.پہلے حدود اللہ قائم کر کے جائز اور ناجائز کی تمیز پیدا کر دی یعنی محل اور غیر محل کی تمیز قائم
کی پھر اِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ کی وضاحت کر کے نیت اور خیال اور ارادہ کی اصلاح کی
اور پھر ہر فعل کو نیک بنانے کا اصول سکھایا اور پھر اخلاق کے مدارج کی تقسیم کر کے گویا
انسانوں کی اخلاقی جماعت بندی کر دی جس کے نتیجہ میں ہر انسان اپنا امتحان خود لے سکتا ہے
117
Page 118
اور فیصلہ کر سکتا ہے کہ وہ مختلف اخلاق کے لحاظ سے کس جماعت اور کس درجہ میں ہے.اور
اس جماعت بندی سے ایک بہت بڑا فائدہ یہ متصور ہے کہ انسان کو اخلاقی ترقی کی طرف
رغبت ہو اور وہ ہمت نہ ہار بیٹھے.جب وہ ایک درجہ میں ہو تو کوشش کرے کہ اس سے اوپر
کے درجہ میں آجائے اور پھر اس سے بڑے اور اس سے آگے کے درجے میں آجائے.اگر وہ
پست سے پست اخلاقی حالت میں بھی ہو تو بھی اس کو خواہش پیدا ہو جائے گی کہ وہ اپنی
اخلاقی اصلاح کی طرف توجہ کرے.اور ہر درجہ پر اس کی ہمت بڑھتی جائے گی اور وہ محسوس
کرتا جائے گا کہ میں نے اس قدر ترقی کر لی ہے.جیسے ایک بچہ جیسے سکول جاتا ہے تو اس کی
توجہ اپنے قریب کے درجوں کی طرف ہوتی ہے اور وہ اس وجہ سے ہمت ہار کے نہیں بیٹھ جاتا
کہ مجھے بی اے، ایم اے کی کتابوں کے نام بھی نہیں آتے.میں بی اے، ایم اے کہاں سے
پاس کر سکتا ہوں.اس کو یہی فکر ہوتی ہے کہ وہ پہلی جماعت سے دوسری جماعت میں چلا
جائے یا دوسری سے تیسری میں یا تیسری سے چوتھی میں.اور جوں جوں وہ ایک جماعت سے
بڑھ کر دوسری میں داخل ہوتا ہے تو اس کی ہمت بلند ہوتی جاتی ہے اور اسے اپنے اوپر ایک
اعتماد پیدا ہو جاتا ہے اور وہ خوشی خوشی اور تیز تیز ترقی کرنے لگتا ہے.البتہ ایک سکول جانے
والے بچے اور ایک عام انسان کی اخلاقی جماعت بندی میں یہ فرق ضرور ہے کہ بچہ عام طور پر
سب مضامین کے لحاظ سے ایک وقت میں ایک ہی درجہ میں ہوتا ہے.گو بعض خاص طور پر
قابل بچوں کو بعض دفعہ خاص خاص مضامین میں اوپر کی جماعت میں بھی شامل کر لیا جاتا ہے
لیکن ایک اخلاق کے کالج کے طالبعلم کی جماعت بندی اس طور پر ہوتی ہے کہ کسی خلق کے
لحاظ سے وہ ایف اے میں ہے اور کسی خلق کے لحاظ سے بی اے میں اور کسی خلق کے لحاظ سے
ایم اے میں یا ان سے نیچے یا اوپر کی جماعتوں میں.پھر خاص خاص اخلاق اور ان کے
دائر عمل اور ان کے آپس میں تطابق سے متعلق اسلام میں تفصیلی بحث اور ہدایات ہیں جنہیں
تم ان کتب میں مطالعہ کر سکتے ہو جن کا میں نے حوالہ دیا ہے.اور یہ مطالعہ تمہیں اس نتیجہ پر
پہنچا دے گا کہ کسی اور مذہب میں اخلاق سے متعلق ایسی تفصیلی تعلیم موجود نہیں ہے جیسی اسلام
118
Page 119
میں ہے.اسی طرح معاشرت، تمدن اور اقتصادیات سے متعلق بھی تفصیلی ہدایات ہیں اور
رعایا اور حکومت سے متعلق اور بین الاقوامی تعلقات سے متعلق.اور ان سب کی کسی قدر
تفصیل " احمدیت یعنی حقیقی اسلام میں بیان کی گئی ہے.ازدواجی زندگی
معاشرت کے ماتحت سب سے اہم تعلقات خاندانی تعلقات ہیں.اور یوں بھی
افراد سے گزر کر سب سے پہلا اور سب سے اہم حلقہ خاندان کا حلقہ ہے اور اس حلقہ کی بنیاد
ازدواجی تعلقات پر ہے.میں بیان کر چکا ہوں کہ اسلام نے ان تعلقات کی بناء تقویٰ کے
قیام اور بقائے نسلِ انسانی پر رکھی ہے.مرد عورت کے درمیان رغبت کا ہونا ایک قدرتی تقاضا
اور جذ بہ ہے اور دوسرے قدرتی جذبات کی طرح یہ جذ بہ بھی اپنی ذات میں نہ برا ہے نہ اچھا
ہے بلکہ اس کا محل استعمال اور جس نیت سے یہ تقاضا پورا کیا جائے اس کے استعمال کو جائز یا
ناجائز اور اچھا یا بُر ابنا دیتے ہیں.محل استعمال کی حد بندی تو اسلام نے نکاح کی شرائط میں
بیان کر دی جو مختصر طور پر یہ ہیں کہ مرد اور عورت کے درمیان کوئی قانونی روک نکاح میں نہ ہو.مثلاً ان کی آپس کی رشتہ داری ایسی نہ ہو جو نکاح سے مانع ہو یا عورت پہلے سے کسی شخص کے
نکاح میں نہ ہو.پھر وہ آپس میں قیام تقویٰ اور بقائے نسل کی نیت سے مستقل ازدواجی رشتہ
قائم کرنے کا فیصلہ کریں.اور اس فیصلہ کا اظہار بصورت ایجاب وقبول گواہوں کے سامنے
کریں.اور اس ایجاب وقبول کا اعلان کر دیا جائے اور ایجاب وقبول کے وقت مرد کی طرف
سے مناسب مہر مقرر کیا جائے اور اس کا بھی اعلان کیا جائے.یہ قانونی یا فقہی شرائط ہیں جو اس تعلق کے لئے بمنزلہ جسم ہیں.لیکن بغیر روح کے یہ
تعلق بھی دوسرے تعلقات کی طرح اپنے حقیقی اغراض و مقاصد کی تکمیل تک نہیں پہنچا سکتا.فتویٰ تو ان شرائط کی تکمیل سے پورا ہو جاتا ہے لیکن تقویٰ کو پورا کرنے کے لئے بعض
119
Page 120
مزید شرائط اور ہدایات اسلام نے بیان کی ہیں.بیوی کے انتخاب سے متعلق رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بعض لوگ
اس انتخاب میں مال کو مد نظر رکھتے ہیں، بعض خاندانی وجاہت کو بعض حسن کو.لیکن ایک مومن
کو چاہئے کہ وہ ان باتوں کو مدنظر رکھے جن پر نکاح کی دینی اغراض کی تکمیل کا انحصار ہے اور
اس کی نیت تقویٰ پر مبنی ہو.قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ اے مومنو! شادی کے معاملہ میں
تقوی کو مد نظر رکھو اور اس سے متعلق فیصلہ کرتے وقت یہ سوچ لو کہ تم آئندہ اپنی زندگی بنا کر
کن باتوں پر رکھ رہے ہو.رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے یہ مراد نہیں کہ مال یا حسن یا خاندانی
وجاہت بُری باتیں ہیں.بلکہ مراد یہ ہے کہ انسان کی نیت اس انتخاب میں دینی اغراض کی
تکمیل ہونی چاہیے اور انتخاب اسی نقطۂ نظر سے ہونا چاہیے اور باقی امور کواسی قدر اہمیت دینی
چاہیے جس قدر ان اغراض کے لحاظ سے ضروری ہو.مثلاً مال کو اس حد تک تو مد نظر رکھنا پڑے
گا کہ خاوند کم سے کم ایسی مالی حیثیت رکھتا ہو کہ بیوی کے لئے مناسب گزارہ کا انتظام کر سکے
اگر ایسا نہ کر سکتا ہو تو قرآن کریم فرماتا ہے کہ اسے عفت کے ساتھ بہتر حالات کا انتظار کرنا
چاہئے.اسی طرح شکل و شباہت کا اتنا لحاظ تو ضرور لازم ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو
پسند ہوں اور کسی فریق کی یہ حالت نہ ہو کہ دوسرے کو دیکھتے ہی کراہت اور نفرت پیدا
ہو جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاء یعنی ایسی عورتوں
سے نکاح کرو جو
تمہیں اچھی لگیں.پھر خاندانی حالات کا اس قد ر لحاظ رکھنا تو ضروری ہوتا ہے
کہ میاں بیوی قریب قریب برابر حالات میں زندگی بسر کرنے کے عادی ہوں ورنہ معاشرتی
امور میں بہت وقت کا سامنا ہو جائے گا.پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے یہ
مراد ہے کہ ان امور کو اپنی ذات میں مقصد نہ بنا لیا جائے مثلاً یہ کہ ایک عورت سے ایک مرد
محض اس لئے نکاح کی خواہش رکھے کہ وہ نہایت حسین ہے یا اس وجہ سے کہ اس کا باپ ایک
ا سورة النساء - آیت 4
↓
120
Page 121
بہت بڑے عہدہ پر ہے یا بہت بڑا امیر ہے.حالانکہ باقی شرائط جو قیام تقویٰ کے لئے
ضروری ہیں یا بقاء نسل کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں وہ موجود نہ ہوں.مثلاً یہ کہ عورت اور اس کا
خاندان دین سے بے بہرہ ہوں اور اس میں کوئی دلچسپی نہ لیتے ہوں یا بد عمل ہوں یا اس
خاندان میں بے غیرتی یا بے حیائی ہو یا عورت کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو جس کا علم ہونے پر
اس سے نفرت ہو جانے کا اندیشہ ہو یا جس کے اثر سے وہ اولاد پیدا کرنے کے نا قابل ہو چکی
ہو.ان سب امور اور دیگر ایسے امور سے متعلق اطمینان کرنے کی ضرورت ہے اور چاہیے کہ
آخری فیصلہ کرنے سے پہلے استخارہ کر لیا جائے تا اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے صحیح انتخاب
کی توفیق
عطا فرمائے.شادی سے متعلق فیصلہ انسان کی زندگی کا سب سے اہم فیصلہ ہوتا ہے جو اس کی
تمام بقیہ عمر اور آئندہ نسلوں پر اثر کرتا ہے اس سے متعلق بہت احتیاط اور فکر اور دعاؤں کی
ضرورت ہے.جب یہ انتخاب ہو چکے تو مرد کو یا درکھنا چاہیے کہ شادی میں عورت کی طرف سے مرد کی
نسبت بہت زیادہ قربانی کی جاتی ہے.اوّل تو اکثر شادیوں میں عورت کی عمر مرد کی نسبت کم
ہوتی ہے اور پھر بہر حال اس کا تجربہ اور علم کم ہوتا ہے پھر اس کی تربیت ایسے رنگ میں اور
ایسے حالات میں ہوئی ہوتی ہے کہ وہ دنیا کے سرد گرم سے محفوظ رہی ہوتی ہے اور اپنے
عزیزوں سے ہر قسم کی محبت اور شفقت کے سلوک کی عادی ہو چکی ہوتی ہے.پھر اُسے شادی
کے بعد اپنے تمام عزیزوں اور اقربا کی صحبت کو ترک کر کے ایک نئے اور اکثر اوقات اجنبی
خاندان کے لوگوں کے ساتھ رشتہ جوڑنا پڑتا ہے اور ایک نسبتا اجنبی مرد کے ہاتھ میں اپنی
زندگی کی باگ دینی پڑتی ہے اور قدرتاً اس سے دل میں اپنے مستقبل سے متعلق کچھ تشویش،
کچھ خوف اور کچھ امنگ ہوتی ہے اور پھر طبعا وہ مرد کی نسبت نازک احساس بھی رکھتی ہے اور
فطرتا اس کے جذبات مرد کے جذبات سے مختلف ہوتے ہیں اور طبعی حیا اور حجاب کی وجہ سے
کم سے کم شروع میں وہ اپنی ضروریات اور خواہشات کا اظہار بھی نہیں کر سکتی.ان حالات
میں اس کے تمام آرام اور تمام خوشی کی ذمہ داری اس کے خاوند پر ہوتی ہے اور اگر اس کی
121
Page 122
طرف سے کمال شفقت اور ہمدردی اور دلداری کا سلوک نہ ہو تو بیوی کے نازک احساس کو
ٹھیس لگنے کا خطرہ ہے جو ممکن ہے ان دونوں کے باہمی تعلقات پر ایک مستقل ناخوشگوار اثر
ڈال دے لیکن ساتھ ہی خاوند کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس کے تعلقات میں تربیتی رنگ ہونا
چاہیے.مگر تربیت کے پہلو میں بھی شفقت اور ہمدردی کا رنگ ہونا لازم ہے اور ابتداء میں
زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ عموماً اُن کے تعلقات کی مستقل صورت آخر جا کر وہی
ہوگی جو شادی کے بعد پہلے چند ماہ یا چند سالوں میں قائم ہو جائے.بیوی کے ساتھ حسن سلوک کا ایک اہم حصہ یہ ہے کہ اس کے والدین اور عزیزوں
کے ساتھ بھی حسن سلوک ہو تا کہ اس کی کسی رنگ میں دل شکنی نہ ہو اور اس کے ناز اور فخر کے
جذبات کو جو وہ قدرتاً اپنے خاوند سے متعلق رکھتی ہے کسی قسم کا صدمہ نہ پہنچے.خاوند قدرتی طور
پر توقع رکھتا ہے کہ بیوی اس کے والدین اور عزیزوں کو اپنے والدین اور عزیزوں کی طرح
سمجھے اور ان کی فرمانبرداری اور تواضع اور خدمت اور احترام ان کے مراتب کے مطابق
کرے.اسی طرح بیوی کو بھی جائز تو قع ہوتی ہے کہ خاوند بھی اس کے والدین اور عزیزوں کو
اپنے والدین اور عزیزوں کی طرح سمجھے اور ان کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرے.قرآن میں آتا ہے لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِى عَلَيْهِنَّ.یعنی عورتوں کے حقوق بھی ویسے
ہی ہیں جیسی کہ اُن پر ذمہ داریاں ہیں.یہ نہیں چاہیے کہ خاوند اپنے حقوق تو پورے کرائے
لیکن عورت کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کرے.اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے
عَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ یعنی عورتوں کے ساتھ حسنِ سلوک کے طریق پر زندگی بسر کرو.پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ یعنی تم سب میں سے
زیادہ نیک وہ ہے جو اپنے اہل کے ساتھ سب سے بہتر سلوک کرتا ہے.عورتوں کی تربیت سے متعلق آپ نے فرمایا ہے کہ عورت ایک نازک خمدار ہڈی کی
سورة البقرة آيت 229
122
سورة النساء - آیت 20
Page 123
طرح ہے اگر نرمی سے اس کی تربیت کرو گے تو جس طرف چاہو گے موڑ لو گے لیکن اگر سختی سے
اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو اندیشہ ہے کہ وہ ٹوٹ جائے.پھر جہاں دو انسانوں نے تمام عمر اکٹھے بسر کرنی ہو وہاں
کبھی کبھی اختلاف بھی ہو جاتا
ہے اور ہوسکتا ہے کہ ایک دوسرے کی بعض باتیں ناپسند بھی ہوں لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ
ایسے عارضی امور پر یا ایسی باتوں پر جو تمہاری طبعیت کے مطابق نہ ہوں جلد بازی نہ کیا کرو.اول تو تمہیں کیا معلوم ہے کہ جس بات
کو تم نا پسند کرتے ہو اس میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے
لئے کوئی بہت بڑی بھلائی رکھی ہو.یا جو بات تمہیں زیادہ مرغوب ہے اس میں تمہارے لئے
کوئی نقصان کی بات ہو اور پھر جب تم ایک ایسی بات کی طرف توجہ کرتے ہو جو تمہاری
طبیعت کے مطابق نہیں تو ان
سینکڑوں باتوں
کو بھی تو یا درکھو جو تمہیں پسند ہیں.با ہمی تعلقات سے متعلق فرمایا کہ تمہارے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کی
محبت ڈال دی ہے تا کہ تم ایک دوسرے سے تسکین اور راحت حاصل کرو اور تم ایک دوسرے کا
لباس بنو.جیسا میں کہہ چکا ہوں ازدواجی تعلقات کی بناء تقویٰ پر ہونی چاہیے.جس طرح باقی
تمام قدرتی تقاضوں اور جذبات کے پورا کرنے میں حسن نیت اور احتیاط لازم ہے اسی طرح
ان تعلقات سے متعلق بھی.انسان کو بھوک لگتی ہے تو وہ کھاتا ہے لیکن اگر کھانے کو اپنی ذات
میں مقصود قرار دے لے تو آہستہ آہستہ سوئے ہضمی پیدا ہو جاتی ہے.پھر عام صحت خراب
ہونے لگتی ہے اور ایسا انسان متواتر کسی نہ کسی عارضہ میں مبتلا ہوتا رہتا ہے.یہی حالت ازدواجی
تعلقات کی ہے کہ برمحل اور اپنی حدود کے اندر تو ان کا استعمال ایک عمدہ خلق ہے لیکن اگر اپنی
حدود سے تجاوز کرے تو محض نفسانیت ہے جس کا اثر انسان کے اخلاق اور روحانیت پر پڑتا
ہے.خاوند کے لئے احتیاط لازم ہے کہ بیوی کے جذبات کو ٹھیس نہ لگے اور اُسے کسی قسم کا
صدمہ نہ ہو
ہ نہ ہو.یہ انسان کی زندگی میں سب سے نازک رشتہ ہے اور اس رشتہ کے ابتدائی ایام
123
Page 124
سب سے نازک مرحلہ ہیں اس لئے ضروری ہے کہ میاں بیوی کے درمیان ایک دوسرے کے
جذبات اور احساسات کا احترام ہمیشہ قائم رہے اور دونوں ایک دوسرے کو ہمیشہ عزت کی نظر
سے دیکھ سکیں.ان تعلقات کو اسلامی معیار کے مطابق سر انجام دینے سے متعلق رسول اللہ
صلے اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے جس سے واضح طور پر معلوم ہو جاتا ہے کہ اسلام ان سے
متعلق کیا نقطہ نظر قائم کرنا چاہتا ہے.حضور نے فرمایا کہ جب تم اپنی بیویوں کے پاس جاؤ تو
یہ دعا کرو.اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَيْبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا.یعنی اے اللہ ہمیں
شیطانی اثرات سے دور کر دے اور اگر تو ہمارے ان تعلقات کے نتیجہ میں اپنے فضل سے
ہمیں اولا د عطا فرمائے تو اسے بھی شیطانی اثرات سے محفوظ رکھیو.رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی اس ہدایت سے ہمیں کئی سبق حاصل ہوتے ہیں.اوّل تو یہی جو میں نے یہاں بیان کیا
ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات کا ایک معیار ہمیں معلوم ہو جاتا ہے اور اس امر کی طرف ہمیں
رہنمائی ہوتی ہے کہ ان تعلقات کے وقت میاں بیوی کی ذہنی کیفیات کیا ہونی چاہئیں اور اس
امر کا پتہ لگتا ہے کہ اس وقت کی کیفیات کا اولاد پر بھی اثر ہوتا ہے اور یہ حقیقت تو اب سائنس
کی تحقیقات سے بھی ثابت شدہ ہے اور پھر اس امر کی طرف توجہ ہوتی ہے کہ اولاد کی تربیت
اور حفاظت اسی وقت سے شروع ہو جانی چاہیے.پھر اگر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اولاد کی صورت کی پیدا کر دے تو مرد کی شفقت اور
دلداری میں کئی گنا اور اضافہ ہو جانا چاہئے کیونکہ یہ وقت عورت کے لئے بڑی ذمہ داری اور
فکر اور خوف کا وقت ہوتا ہے اور ایا م جمل میں عورت پر دو جانوں کی ذمہ داری ہوتی ہے اور
اس کی صحت کی یہ حالت ہوتی ہے کہ اُسے اپنی طبیعت سنبھالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اس لئے
ان ایام میں ہر وقت اس کی دلداری مد نظر رہنی چاہئے اور خانہ داری سے متعلق جس قدر
ہو سکے اس کی ذمہ داری میں تخفیف کر دینی چاہئے اور خوراک اور چلنے پھرنے اور تازہ ہوا
وغیرہ سے متعلق احتیاط ہونی چاہئے اور ہر قسم کے جسمانی اور ذہنی صدمے سے اُسے محفوظ
124
Page 125
رکھنا چاہئے اور خاوند کی توجہ اور محبت اور شفقت اس زمانہ میں اور بھی بڑھ جانی چاہئے.قرآن کریم نے بھی عورت کی اس کیفیت کی طرف توجہ دلائی ہے جہاں فرمایا ہے کہ
اولا دکو یا درکھنا چاہیے کہ کسی تکلیف اور بے چینی کی حالت میں ماں نے اسے اٹھائے رکھا اور
اُسے جنا اور پھر اس کی پرورش میں مصروف رہی.خاوند کو چاہئے کہ شفقت اور ہمدردی اور توجہ کے علاوہ اس عرصہ میں دعاؤں میں
مصروف رہے کہ یہی طریق سب سے بہتر ہمدردی کے اظہار کا ہے اور یہ دعائیں صرف بیوی
کے لئے نہ ہوں بلکہ ہونے والے بچے کو بھی ان میں شامل کیا جائے.اسلام نے بچے کی پیدائش کے موقعہ پر پھر اس کی تربیت کی طرف توجہ دلائی ہے.بچہ کے پیدا ہوتے ہی اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر کہنے کا حکم ہے.اس میں بھی یہ حکمت ہے کہ والدین کو توجہ دلائی جائے کہ ابھی سے بچے کی تربیت کی طرف
تو جہ اور ان اصولوں اور ان مقاصد کو مد نظر رکھ کر اس کی تربیت ہونی چاہئے جو اذان میں
بیان کئے گئے ہیں.موجودہ زمانہ میں عورت مرد کی مساوات کا بہت چرچا رہتا ہے اور جس طرح باقی
امور میں دنیا افراط و تفریط کی طرف جارہی ہے اسی طرح اس معاملہ میں بھی بعض لوگ ایک
طرف حد سے آگے نکل گئے ہیں اور بعض لوگ دوسری طرف.قرآن کریم نے ایک طرف
تو اس مساوات کو یہ کہکر قائم کیا ہے کہ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ.یعنی عورتوں کو ویسے
ہی حقوق ہیں جیسی کہ ان پر ذمہ داریاں ہیں اور دوسری طرف اس امر کی بھی وضاحت کر دی
ہے کہ اس اشتراک میں جو عورت اور مرد کے درمیان قائم ہوتا ہے سینئر شریک مرد ہے.بے شک بحیثیت انسان مرد اور عورت دونوں برابر ہیں لیکن قدرت نے جو اختلاف دونوں
کے درمیان رکھا ہے وہ خود اس بات پر شاہد ہے کہ حیات انسانی میں دونوں کا حلقہ عمل اور
دونوں کے فرائض ایک دوسرے سے بہت حد تک مختلف ہیں.اس حلقہ عمل اور ان کے
سورة البقرة آیت 229
125
Page 126
فرائض کو مد نظر رکھتے ہوئے مرد پر زندگی کے نسبتا کرخت فرائض اور بھاری ذمہ داریاں لگائی
گئی ہیں اور عورت کے سپر دنسبتا نازک کام کئے گئے ہیں اور انہیں فرائض اور ذمہ داریوں کے
مطابق اُن کی جسمانی ساخت اور اُن کے قومی کی طاقت اور تربیت بھی ہے تا کہ وہ اپنی اپنی
ذمہ داریوں کو احسن طریق پر سرانجام دے سکیں.مثلاً مرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی محنت
سے اپنے لئے اور اپنی بیوی بچوں کے لئے روزی کمائے اور ان کے آرام کے سامان
حتی المقدور مہیا کرے اور اُن کی حفاظت کرے اور ہر قسم کے خطرات کے مقابلہ میں ان کے
لئے ایک سپر ہو.دنیا میں جہاں بھی شراکت ہوگی وہاں لازماً ایک شریک کو دوسروں کی نسبت کچھ
اختیارات زیادہ دیئے جائیں گے تا کہ اختلاف کی صورت میں اسے آخری فیصلہ کا اختیار ہو.یہ اختیارات ہر موقعہ اور محل پر استعمال نہیں ہوں گے.بلکہ میاں بیوی کا رشتہ تو ایسا ہے کہ اگر
دونوں اپنے اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کو مدنظر رکھیں تو ایسے اختیارات کے استعمال کے
مواقع بھی پیدا نہیں ہونے چاہئیں.لیکن اگر ان کے استعمال کا موقع پیدا ہوتو معلوم ہونا
چاہئے کہ یہ اختیارات کسے حاصل ہیں.اسلام نے تو رفع اختلافات کا اس حد تک انتظام کیا
ہے کہ چھوٹے سے سفر کو بھی اس دائرہ سے باہر نہیں رکھا اور تاکید کی ہے کہ جب دو یا دو سے
زیادہ لوگ اکٹھے سفر کے لئے نہیں تو اپنا ایک امیر مقرر کرلیں اور سفر کے دوران میں اُس کی
اطاعت کریں.اور میاں بیوی کا ساتھ تمام زندگی کے سفر کا ساتھ ہے اس سفر کا بھی تو کوئی
امیر ہونا چاہئے.اور اس سفر کا امیر اسلام نے مرد کو مقرر کیا ہے.اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ
روزی کمانا اور مال کا بہم پہنچانا اُس کے ذمہ ہے اس لئے اس مال کے خرچ کرنے اور دیگر
انتظامات وغیرہ سے متعلق بھی اُسے آخری فیصلہ کا اختیار ہونا چاہیے.لیکن تم پڑھ چکے ہو کہ
اسے حسنِ سلوک اور نرمی اور شفقت اور ہمدردی کی کس قدر تاکید کی گئی ہے.بعض لوگ جو بالکل دوسری طرف نکل گئے ہیں وہ عورت کو انسانیت کا درجہ بھی نہیں
دیتے اور ہر اختیار سے اسے کلی طور پر محروم کر دیتے ہیں اور اس کی حیثیت گھر میں زیادہ سے
126
Page 127
زیادہ ایک غلام کی رہ جاتی ہے حالانکہ یہ طریق اسلام کی تعلیم کے بالکل خلاف ہے.جو حدود
اسلام نے مقرر فرمائی ہیں ان کے اندر اندر عورت کو اُسی قسم کی آزادی فکر اور غور اور تجویز اور
فیصلہ اور عمل کی ہونی چاہیئے جیسی کہ مرد کو اس کے اپنے حلقہ عمل میں ہے ورنہ گھر کا انتظام
خوش اسلوبی سے نہیں چل سکتا اور اُس کے کئی پہلو ادھورے رہ جانے کا احتمال ہے جو مرد کے
لئے بھی پریشانی اور زحمت کا باعث ہوگا اور عورت کے لئے بھی اور اس کا اثر بچوں کی تربیت
پر بھی پڑے گا.تربیت اولاد
پھر جب بچے پیدا ہو جائیں اور ایک گھرانے کی صورت بن جائے تو ایک طرف
ماں باپ کو ہدایت ہے کہ وہ بچوں کی تربیت نرمی اور شفقت سے کریں اور دوسری طرف بچوں
کو ہدایت ہے کہ وہ ماں باپ کی فرمانبرداری اور ان کی عزت کریں اور ان کے ساتھ احترام
سے پیش آئیں.اور جوں جوں بچے بڑے ہوتے جائیں اور ماں باپ بوڑھے ہوتے
جائیں بچوں کی طرف سے محبت اور شفقت کا اظہار بڑھتا جائے اور پورے طور پر ماں باپ
کی خدمت بجالائیں.تربیت اولاد سے متعلق ایک اصول رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے نہایت لطیف
طریقہ پر سکھایا ہے جس کی طرف عام طور پر بہت کم توجہ کی گئی ہے آپ نے فرمایا ہے اسحرِ مُوا
أَوْلَادَكُمْ یعنی اپنی اولاد کا اکرام کرو یعنی محبت اور شفقت کے علاوہ اُنکے ساتھ عزت سے
پیش آؤ.ایسے سلوک کے نتیجہ میں اولاد کے دل میں اپنے پر اعتماد بڑھے گا.اس کی ہمت بلند
ہوگی ، اور وہ عمدہ آداب و اخلاق آسانی سے سیکھ سکے گی.افسوس ہے کہ ہمارے ملک میں
والدین اولاد کی تربیت کی طرف بہت کم توجہ کرتے ہیں.ماؤں کو تو مجبوراً کسی حد تک توجہ
کرنی پڑتی ہے لیکن باپ عموماً اس ذمہ داری کے اٹھانے سے گریز کرتے ہیں اور صرف یہی
127
Page 128
کافی سمجھتے ہیں کہ بچے کو چھوٹی عمر سے ہی کسی استاد کے سپرد کر دیا یا کسی بورڈ نگ یا سکول میں
بھیج دیا حالانکہ ماں باپ کی ذاتی توجہ کی جگہ کوئی اور چیز نہیں لے سکتی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ماں
باپ اور اولاد کے درمیان ایک اجنبیت پیدا ہو جاتی ہے جو بعد میں پھر کبھی دور نہیں ہوسکتی اور
دونوں طرف ایک ایسا حجاب قائم ہو جاتا ہے جو قدرتی جذبات کے اظہار میں روک ہو جاتا
ہے.اور ایک طرف اولاد ایک بہت بڑے فائدہ سے محروم ہو جاتی ہے اور دوسری طرف
ماں باپ اور خصوصاً باپ اس محبت کا مورد ہونے سے محروم ہو جاتا ہے جو قدرتی طور پر اولاد
کے دل میں والدین کے لئے ہوتی ہے.رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مَنْ لَّمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَ لَمْ يُؤَقِرْ
كَبِيْرَنَا لَيْسَ مِنا.یعنی جو شخص اپنے بڑوں کا ادب نہیں کرتا اور چھوٹوں سے شفقت اور رحم
سے پیش نہیں آتا وہ ہم میں سے نہیں ہے.ایک طرف بیوی اور اولاد سے متعلق اس قدر
حسنِ سلوک اور محبت اور شفقت کی تاکید ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تاکید ہے کہ بیوی
اور اولاد کی محبت تمہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہ کر دے.اور یہ کہ بیوی بچے تمہارے
لئے ایک امتحان میں امتحان اس لحاظ سے اول تو جو سلوک تم ان کے ساتھ کرو گے وہ خود تمہارا
امتحان ہے ایسا نہ ہو کہ ان کے حقوق کی ادائیگی میں غفلت یا سستی یا سختی سے کام لو اور تقویٰ
سے گر جاؤ اور دوسری طرف یہ اس لحاظ سے آزمائش ہیں کہ یہ تمہیں ذکر اللہ سے غافل نہ
کر دیں.اور ان کی محبت تمہارے لئے مقصود بالذات نہ ہو جائے اور ان کی خواہشات اور
ضروریات کو پورا کرنے کی خاطر تم خلاف تقویٰ راہیں اختیار نہ کرنے لگو.مثلاً کئی لوگ ہیں
جو بیوی بچوں کی ضروریات پوری کرنے کے لئے رشوت لینے لگتے ہیں یا فریب اور دھو کہ
سے مال حاصل کرنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں.غرض یہاں بھی اسلام نے حد بندی کر دی
ہے کہ بیوی بچوں سے محبت ایک پسندیدہ خلق ہے بشرطیکہ نیت اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول ہو،
نہ کہ اپنی نفسانی خواہشات اور ضروری ہے کہ یہ محبت اپنے مناسب حلقہ تک محدود در ہے.اس کے مقابل پر اولا د کو ماں باپ کے احترام اور ان کی فرمانبرداری اور ان کے
128
Page 129
ساتھ حسنِ سلوک کی سخت تاکید کی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا
إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَهُمَا فَلَا تَقُلْ
لَّهُمَا اُتٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ۖ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ
الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّينِي صَغِيرًا.یعنی تیرے رب نے حکم دیا ہے کہ
تم سوا اُس کے اور کسی کی عبادت نہ کرو اور اپنے والدین کے ساتھ نیکی کے ساتھ پیش آؤ.اگر
ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو تم انہیں اُف تک نہ کہو.اور ان کے ساتھ
سختی سے کلام نہ کرو اور اُن کے ساتھ محبت اور شفقت کے ساتھ کلام کرو.اور ان کے لئے
رحمت کے ساتھ نرمی اور بجز کے پر بچھائے رکھو.اور ان کے لئے یہ دُعا کرتے رہو کہ اے
میرے رب تو ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے میری پرورش اور تربیت کی جبکہ میں چھوٹا سا
تھا اور بالکل بے بس تھا.ان آیات میں ایک امر خصوصیت سے قابل غور ہے اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے والدین کی
فرمانبرداری اور ان کے ساتھ حسن سلوک کو عین اپنی توحید کے بعد رکھا ہے جس سے پتہ لگتا ہے
کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک والدین کے احترام اور ان کی خدمت کو بڑا درجہ حاصل ہے.اسی طرح درجہ بدرجہ سب رشتہ داروں کے ساتھ اسلام میں حسن سلوک کی تعلیم ہے
درجہ رشتہ ساتھ
بلکہ تم دیکھ چکے ہو کہ اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ اخلاق کی تعریف ہی اللہ تعالے نے یہ فرمائی ہے کہ نیکی
انسان کی سرشت میں اس طرح سرایت کر جائے جیسے رشتہ داروں کے ساتھ حسنِ سلوک کی
خواہش قدرتی طور پر انسان کے اندر جوش زن ہوتی ہے.چنانچہ فرمایا: وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتْمَى وَالْمَسَكِيْنِ
وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ
وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ.یعنی والدین کے ساتھ احسان کے ساتھ پیش آؤ اور
رشتہ داروں کے ساتھ اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اور قریب کے پڑوسی کے ساتھ اور دُور
سورة بنی اسرائیل.آیات 25-24
سورة النساء - آیت 37
129
Page 130
کے پڑوسی کے ساتھ اور اپنے شرکاء کار کے ساتھ اور مسافروں کے ساتھ اور غلاموں کے
ساتھ.اور پھر جانوروں کے ساتھ عمدہ برتا ؤ اور ان پر رحم کرنے سے متعلق بھی ہدایات ہیں.عام تمد فی آداب
پھر اسلام نے آداب طعام بیان فرمائے ہیں اور مجالس سے متعلق قواعد بیان فرمائے
ہیں اور ہر قسم کے تمدنی اور معاشرتی اخلاق اور قواعد کی تشریح بیان کی ہے اور مومن کو اخلاق
اور وقار کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی ہدایت دی ہے.مثلاً یہاں تک تفصیل ہے کہ مجالس
میں پیچھے آنیوالوں کے لئے جگہ کر دیا کرو، صدر کی اجازت کے بغیر مجلس سے اٹھ کر نہ جاؤ.اور
وقار کا یہاں تک لحاظ رکھا ہے کہ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بازاروں میں
کھڑے ہو کر نہ کھاؤ پیو اور یہ کہ ایک پاؤں میں جوتا پہن کر مت چلو.یعنی یا تو دونوں پاؤں
میں جوتا ہو یا دونوں ننگے ہوں.پھر رستوں کی صفائی اور رستوں سے باعث آزار اشیاء کوڈ ورکرنے کی ہدایت کی ہے.پھر تاجروں کے لئے مختلف قسم کی ہدایات ہیں جن سے مقصد یہ ہے کہ ہر شخص کو اپنا پورا
حق ملے اور کسی قسم کا دھو کہ یا فریب نہ ہو.محض خریدار ہوشیار باش پر اکتفا نہیں کی بلکہ بیچنے
والے کا فرض مقرر کیا ہے کہ وہ اپنی اشیاء کی اصل حقیقت بیان کر دے اور کسی قسم کا دھوکہ نہ ہو.انجمنوں اور سوسائٹیوں سے متعلق فرمایا ہے کہ تین اغراض کے لئے قائم ہوں.اوّل
جن کی غرض غرباء اور مساکین کی مدد ہو.دوم جن کی غرض علوم وفنون کی ترقی اور علمی تحقیق کی
ترویج ہو.سوم جو بنی نوع انسان کے درمیان صلح اور اتحاد کو پھیلانے کی غرض سے ہوں خواہ
قومی حلقہ کے اندر خواہ بین الاقوامی حلقوں میں.غرض ایسے ایسے پاکیزہ اصول بیان کئے ہیں جن پر عمل کرنے سے یہ زندگی سچ سچ
بہشت بن جاتی ہے چاہیے کہ تم ان سب کا تفصیلاً مطالعہ کرو.اور ان پر کار بند ہوتے جاؤ.130
Page 131
اقتصادی نظام
اب میں اسلام کے اقتصادی نظام سے متعلق مختصر ا چند اصول بیان کرتا ہوں.کیونکہ
آج کل مغرب میں ان امور سے متعلق بہت بحث مباحثہ رہتا ہے اور ان میں بھی افراط اور
تفریط کی راہیں اختیار کی گئی ہیں.اور ہمارے نوجوان اسلام کی تعلیم پر غور کئے بغیر اپنے لئے
بعض رستے تجویز کر لیتے ہیں جو ان کی زندگیوں پر بہت مضر اثر ڈالتے ہیں.اول تو یہ امر ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ اسلام نے تمام امور میں ایک زریں اصل
مقرر کیا ہے اور وہ یہ ہے خَيْرُ الْأُمُوْرِ أَوْسَطُها یعنی ہر معاملہ میں درمیانی رستہ سب سے
بہتر ہوتا ہے.اقتصادیات میں بھی اسلام نہ تو کلی طور پر انفرادیت کا حامی ہے اور نہ کلّی طور پر
اشتراکیت کا.اسلام ایک حد تک انفرادی ملکیت کے اصول کو تسلیم کرتا ہے.کیونکہ اول تو مختلف
انسانوں کی مختلف استعدادیں ہوتی ہیں پھر بعض ان استعدادوں کو صحیح طور پر استعمال کرتے
ہیں اور بعض نہیں کرتے.اور ہر ایک قسم کے استعمال کے درجے ہیں اور پھر مختلف انسان
مختلف معیاروں کے مطابق کام اور محنت کرتے ہیں اس لئے لازم ہے کہ اُن کی استعدادوں
اور اُن کی محنت کا اجر بھی مختلف پیمانوں کے مطابق ہو.اور پھر انسانی فطرت ہی ایسی ہے کہ
اگر انفرادی اجر اور ملکیت کی طمع نہ ہو تو اکثر انسان اپنی استعدادوں کو پورے طور استعمال
کرنے اور پوری محنت کرنے پر آمادہ نہیں ہوتے.لیکن انفرادیت ملکیت کے اصول کو تسلیم کر
لینے کے بعد اسلام نے اس پر کئی قسم کی پابندیاں لگادی ہیں جن کے نتیجہ میں اس اصول کے
انتہائی استعمال سے جو خرابیاں پیدا ہونے کا اندیشہ ہے اس کا خود بخودازالہ ہو جاتا ہے.مثلاً اسلام کا بنیادی اقتصادی اصول یہ ہے کہ دولت کے پیدا کرنے میں صرف
سرمایہ دار اور کام کرنے والے مزدور کا ہی دخل نہیں بلکہ دوسرے لوگوں کا بھی حصہ ہے ظاہر
ہے کہ دنیا کا اصل سرمایہ جس سے آخر میں تمام قسم کی دولت پیدا ہوتی ہے یعنی زمین اور اُس
131
Page 132
کے تمام خزائن اور طاقتیں اور ہوا، سورج چاند ستارے وغیرہ وہ سب اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں
جو اس نے اپنی طرف سے انسانوں کو ہبہ کی ہیں تو گویا دولت کے پیدا کرنے میں ایک تو
سرمایہ دار شامل ہوتا ہے دوسرے مزدور اور تیسرے تمام بنی نوع انسان جن کی خدمت کے
لئے اللہ تعالیٰ نے یہ تمام کائنات پیدا کی ہے.اس لئے دولت میں صرف سرمایہ دار اور مزدور
کا ہی حصہ نہیں نکالنا چاہیے بلکہ عام بنی نوع انسان کا حصہ بھی نکالنا چاہیے اور اسلام نے اس
حصہ کا نام زکوۃ رکھا ہے جس کے نام سے ہی ظاہر ہوتا ہے کہ اگر یہ حصہ نہ نکالا جائے تو باقی
حصہ دولت کا پاک نہیں ہوتا.کیونکہ اس دولت میں کسی اور کا حصہ بھی شامل ہے اور جب تک
سب حصہ داروں کے حصے نہ نکالے جائیں دولت کی تقسیم جائز نہیں سمجھی جاسکتی.لیکن زکوة
محض صدقہ یا خیرات نہیں جیسے عام طور پر آجکل خیال
کر لیا گیا ہے بلکہ یہ ایک ٹیکس ہے جو
راس المال اور آمد دونوں پر لگتا ہے اور اس کا ادا کرنا ہر اس شخص پر فرض ہے جو صاحب نصاب
ہے اور اس کے متعلق قرآن کریم میں بار بار تاکید آئی ہے.اسلام میں زکوۃ کی شرح مقرر
ہے اور اُس کے خرچ کے مقاصد مقرر ہیں.حکومت کا فرض ہے کہ اس ٹیکس کو جمع کر کے صرف
ان مقاصد پر خرچ کرے جو اس کا جائز مصرف ہیں.حکومت کو اختیار نہیں کہ اسے اپنے عام
فرائض کی تکمیل میں خرچ کرے مثلاً زکوۃ کا اول مصرف تو یہ ہے کہ جو عملہ اس کے جمع کرنے
پر مقرر ہو اس کی اُجرت اس میں سے ادا ہو.پھر غرباء اور مساکین کی پرورش اور اُن کی ترقی
کے سامان بہم پہنچائے جائیں.پھر ایسے لوگوں کو وظائف دیئے جائیں جو علمی تحقیقات اور
ایجادوں وغیرہ میں لگے رہتے ہیں اور اپنی روزی نہیں کما سکتے.پھر ایسے لوگوں کے لئے بھی
اسی میں سے سرمایہ بہم پہنچایا جائے جوکسی پیشہ یافن یا صنعت وحرفت میں مہارت رکھتے ہیں
لیکن سرمایہ نہیں رکھتے کہ کام شروع کر سکیں.افسوس کہ مسلمانوں نے زکوۃ کی ادائیگی اور اُس کے مصرف کے انتظام کو ترک کر دیا
ہے ورنہ اکثر اقتصادی مشکلات اور ضروریات کا حل اس میں موجود تھا.132
Page 133
سود کی ممانعت
پھر اسلام نے سُود منع فرمایا ہے کیونکہ اول تو اس سے یہ قباحت پیدا ہوتی ہے کہ انسانی
ہمدردی اور اخوت کا احساس آہستہ آہستہ مٹ جاتا ہے پھر سود پر لین دین کرنے کے نتیجہ میں
دولت سمٹ کر چند آدمیوں کے ہاتھوں میں جمع ہو جاتی ہے اور باقی حصہ ملک یا سوسائٹی کا مالی
طور پر اُنکی غلامی میں آجاتا ہے.بے شک چند لوگ تو اس کے نتیجہ میں کروڑ پتی ہو جاتے ہیں
لیکن اس کے مقابل پر کروڑوں لوگ مفلس اور نا داررہ جاتے ہیں اور اسلام کا نقطہ نگاہ یہ ہے
کہ دولت ایک طبقہ کے ہاتھوں میں جمع نہ ہو جائے بلکہ مختلف طبقوں کے درمیان چکر لگاتی
رہے اور زیادہ سے زیادہ افراد میں تقسیم ہوتی رہے.پھر جو لوگ استعداد اور قابلیت رکھتے
ہوں اُس کو بڑھالیں اور یہ پھر تقسیم ہو جائے.قرآن کریم میں یہ وعید بھی آتا ہے کہ سود پر
لین دین کے نتیجہ میں جنگ ہوتی ہے.چنانچہ پچھلی جنگ کے موقعہ پر یہ امر مشاہدہ میں آچکا
ہے کہ اگر سُود پر قرضہ لینے کا رواج نہ ہوتا تو جنگ اس قدر بھی نہ چل سکتی.اور موجودہ ایام میں
بھی جو آئندہ ایک خوفناک جنگ کی تیاری کے لئے بے انداز سامانِ حرب تیار ہورہا ہے اس
کی بناء بھی زیادہ تر سودی قرضہ پر ہی ہے.اگر یہ رواج نہ ہو تو مختلف اقوام کی جنگی تیاری
بہت ہی ادنی پیمانہ پر ہو جس سے نہ تو اس قدر مالی بوجھ قوموں پر پڑے اور نہ اس قدر تباہی کا
خطرہ پیدا ہو.لیکن اس سے یہ قیاس نہ کر لینا چاہیے کہ اسلام نے قرضہ لینے یا دینے کو ہی منع کر دیا
ہے یار بہن کا طریق منع قرار دیا ہے یا تجارتی شراکتوں سے منع فرمایا ہے بلکہ اسلام نے جائز
ضرورت کے لئے سود سے بچتے ہوئے قرضہ جائز رکھا ہے.مگر قرضہ سے متعلق اسلام کا حکم
ہے کہ وہ تحریر میں آنا چاہئے، خواہ تھوڑی رقم ہو خواہ بڑی اور اس پر شہادت ثبت ہونی چاہیے.اور ادائیگی قرضہ کی معیاد مقرر ہونی چاہئے اور یہ تحریر مقروض کے کہنے اور اسکے لکھوانے پرلکھی
جانی چاہیے.اور اگر مقروض نابالغ یا فاتر العقل ہو تو اس کے ولی کے لکھوانے پر لکھی جانی
133
Page 134
چاہیے.اور اسی طرح باقی معاہدات سے متعلق حکم ہے کہ وہ تحریر میں آنے چاہیے.لیکن ان سب معاہدات اور شراکتوں وغیرہ سے متعلق حکم ہے کہ ان کی بنا ءسود پر نہ.اور سُود سے مراد یہ ہے کہ ایک فریق شرط کرے کہ وہ روپیہ یا جنس کے استعمال کے بدلے
میں ایک مقررہ رقم یا ایک مقررہ شرح پر رقم یا جنس ادا کرے گا ہاں اگر تجارتی اصول پر شراکت
کی صورت ہو جس میں دونوں فریق ایک مقررہ شرح پر نفع اور نقصان دونوں کے حقدار اور
ذمہ دار ہوں تو یہ صورت بالکل جائز ہے اور قابل اعتراض نہیں.اسلامی قانونِ وراثت
تیسری روک جو اسلام نے دولت کے چند ہاتھوں میں جمع ہو جانے پر عائد کی ہے وہ
اسلامی طریق وراثت ہے.ایک بالغ عاقل مسلمان اپنی زندگی میں اپنی جائداد کا جو حصہ
چاہے ہبہ کر دے یا جیسے چاہے صرف کرے اسے اختیار ہے بشرطیکہ ہبہ کرنے کے ساتھ ہی وہ
جائداد پر سے اپنا تصرف ہٹالے.مثلاً یہ نہیں کر سکتا کہ کوئی ایسا انتظام کر دے کہ اپنی حیات
میں تو خود فائدہ اٹھاتا رہے لیکن اپنے مرنے کے بعد وہ جائداد کسی اور کی سمجھی جائے.لیکن ہبہ
کرنے کا اختیار بھی اس کو اسی وقت تک ہے جب تک وہ صحت کی حالت میں ہے جب
مرض الموت شروع ہو جائے تو پھر وہ ہبہ نہیں کر سکتا البتہ وصیت کر سکتا.لیکن وصیت کی رُو
سے اپنی کل جائداد کے 1/3 حصہ سے زائد کا انتقال نہیں کر سکتا حتی کہ خیراتی یا دینی اغراض
کے لئے بھی اس سے زیادہ کا انتقال وصیت کی رُو سے نہیں کر سکتا اور اس 1/3 حصہ سے متعلق
بھی یہ پابندی ہے کہ اس کا کوئی حصہ اپنے کسی وارث کے حق میں وصیت نہیں کر سکتا کیونکہ
اس کا لازماً نتیجہ یہ ہوگا کہ اس وارث کا حصہ وصیت کنندہ کی جائداد میں اپنی قسم کے دیگر ورثاء
کے مقابلہ میں بڑھ جائے گا کیونکہ ایک تو وہ اپنا مقررہ حصہ لے گا اور پھر وصیت کی رُو سے
زائد لے گا.اس لئے ایسا کرنا منع ہے اور نہ کسی مسلمان کے لئے یہ جائز ہے کہ وہ اپنے کسی
134
Page 135
وارث کو وراثت سے محروم کر دے یا اس کا حصہ کم کر دے.اور شرعاً یہ بھی ناجائز ہے.(گو
فقہ کی رو سے ایسی کوئی پابندی نہیں) کہ اپنی زندگی میں کچھ جائداد ایک وارث کو دیدے جب
تک دیگر ورثاء کو بھی اس کے مقابلہ میں اُن کے حصہ کے برابر جائداد نہ دے.اور وصیت
کے بعد جو ترکہ بیچ رہے اس میں سے اول تو متوفی کی تجہیز و تکفین کے مصارف ادا کئے جائیں
پھر اس کے قرضے ادا کئے جائیں اور پھر جو خالص ترکہ بچے وہ اس کے ورثاء میں ان کے
مقرر شدہ حصوں کے مطابق تقسیم ہو.اسلامی قانونِ وراثت کے ماتحت ایک شخص کے مرنے
کے بعد اس کی بیوہ یا بیوگان والد.والدہ بیٹے.بیٹیاں جو بھی زندہ ہوں سب وارث ہوتے
ہیں البتہ برابر کے درجہ کے وارثوں میں مرد کا حصہ عورت کے حصہ سے دُگنا ہوتا ہے.ورثاء
کی اس کثرت کی وجہ سے ایک مسلمان کا ترکہ بہت جگہ تقسیم ہو جاتا ہے اور وراثت ایک ہی
جگہ جمع نہیں ہوتی.غیر مسلموں کی طرف سے بعض دفعہ یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ مرد کا حصہ عورت کے
حصّہ سے زیادہ کیوں رکھا گیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اسلامی قانون کے ماتحت خاوند خواہ
کتنا ہی تنگدست ہو اور بیوی کے پاس خواہ کتنی ہی جائداد ہو خاوند کا فرض ہے کہ وہ اپنی جائداد
کی آمدنی سے یا اپنی کمائی میں سے بیوی اور بچوں کی پرورش کا انتظام کرے اور ان کے جملہ
اخراجات کا متحمل ہو.تو گویا ہر مرد کے ذمہ اپنی بیوی اور بچوں کی پرورش لگائی گئی ہے اور عورت
خواہ کیسی ہی مالدار ہو اس کے ذمہ یہ فرض نہیں لگایا گیا.چونکہ مرد پر یہ فرض عائد کیا گیا ہے اور
عورت اس سے آزاد ہے اس لئے وراثت میں مرد کا حصہ عورت کی نسبت دگنار کھا گیا ہے.پھر ورثاء کی ایک ذمہ داری یہ ہے کہ اگر ایک شخص معذور ہے اور اپنے گزارہ کا انتظام
نہیں کر سکتا اور نہ ایسی جائدا درکھتا ہے جسے وہ اپنے گزارہ کی سبیل بنا سکے تو ان لوگوں کا جو اس
کے مرنے پر اس کے وارث ہوتے ہیں فرض ہے کہ حصہ رسدی اس کے گزارہ کا انتظام
کریں.غرض اسلام نے ایک ایسا اقتصادی نظام قائم کیا ہے کہ جس کے ماتحت انفرادیت اور
135
Page 136
اشتراکیت کے مفید عصر جمع کر دیئے گئے ہیں اور دونوں کی افراط و تفریط کو رڈ کر دیا گیا ہے یا
اس اصلاح کر دی گئی ہے.اسی طرح اسلام میں حکومت اور رعایا کے حقوق اور فرائض اور
تعلقات سے متعلق تفصیلی احکام اور قواعد ہیں اور بین الاقوامی تعلقات سے متعلق ہدایات ہیں
غرض انسانی زندگی کا کوئی پہلو یا تعلق ایسا نہیں جس سے متعلق اصولی ہدایات نہ دی گئی ہوں.موت کی حقیقت
اب میں نہایت مختصر طور پر موت کے بعد کے حالات سے متعلق اسلام کی اصولی تعلیم
اپنے ذوق کے مطابق بیان کرتا ہوں.اوّل یہ امر ذہن نشین کرنا چاہیے کہ موت اپنی ذات میں مصیبت یا دکھ کی چیز نہیں.بے شک ایک عزیز کی اس دنیا میں مفارقت پر دل کو جدائی کا دکھ ہوتا ہے.یہ ایک قدرتی
جذبہ ہے لیکن موت خود اپنی ذات میں قابل افسوس نہیں جب بیٹا تعلیم کی خاطر ماں باپ سے
جد ا ہوتا ہے تو بیٹے اور ماں باپ دونوں کو رنج ہوتا ہے لیکن وہ جدائی جس کی وجہ سے رنج ہوتا
ہے اپنے اندر ایک خوشی کی چیز ہوتی ہے اسی طرح اگر روزی کمانے کے لئے کسی شخص کو اپنے
بیوی بچے سے ایک لمبے عرصہ کے لئے جدائی اختیار کرنی پڑتی ہے تو دونوں فریق کو جُدائی کا
رنج ہوتا ہے.یا جب لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو گو یہ تقریب اپنے اندر خوشی کی تقریب ہوتی
ہے اور اس نے تعلق سے جو اس وقت قائم ہوتا ہے کئی قسم کی برکتوں اور ترقیوں کی امید کی
جاتی ہے لیکن اس موقعہ کے لحاظ سے قدرتی طور پر ماں باپ کو بیٹی کی جدائی کے احساس سے
اور بیٹی کو ماں باپ اور دیگر عزیزوں کی جدائی کے احساس سے تکلیف ہوتی ہے.یہی حالت
ایک عزیز کی موت کے وقت اس کے عزیزوں کی ہوتی ہے.اگر چہ موت کیوجہ سے جو جدائی
ہوتی ہے وہ چونکہ ایک شخص کو اُس کے عزیزوں سے ظاہری طور پر ہمیشہ کے لئے جدا کر دیتی
ہے اس لئے جدائی کا یہ صدمہ زیادہ ہوتا ہے.لیکن موت اپنی حقیقی صورت میں اللہ تعالیٰ کی
136
Page 137
رحمت ہی ہے جو پیچھے رہتے ہیں ان کے لئے بھی اور جو چلا جاتا ہے اس کے لئے بھی.گوئین
جُدائی کے وقت یہ رحمت کا پہلو ہماری نظروں سے اوجھل ہوتا ہے اور صدمہ کا احساس اس
قدر تیز ہوتا ہے کہ دوسرے سب پہلو اس کے نیچے دب جاتے ہیں.مثلاً غور کرو کہ ہمارے سب وہ بزرگ جن کی جدائی کا صدمہ ہم اب تک محسوس کرتے
ہیں آج زندہ ہوتے اور پھر ان وہ کے بزرگ جن کی جدائی کا صدمہ انہوں نے محسوس کیا اور
جن کی موجودگی کی انہیں خواہش اور حسرت تھی اور پھر ان کے بزرگ اور پھر ان کے بزرگ
اور اسی طرح ایک لا انتہا سلسلہ تک سب زندہ ہوتے تو اول تو اس زمین پر چلنے پھرنے اور
ہلنے جلنے کی جگہ ہی نہ ہوتی.اور پھر موجودہ نسلوں کی ترقی کرنے کا کوئی میدان میسر نہ ہوتا
اور تمام اہم امور کی سرانجام دہی ہمارے بزرگوں کے بزرگوں کے بزرگوں سے کئی سونسلیں
اوپر کے بزرگوں کے ہاتھ میں ہوتی اور دنیا ایک عجیب مشکل اور مصیبت کی جگہ بن جاتی.اور
آج ہی پر غور کر کے دیکھو اگر چہ تم ہمیں بہت پیارے ہو اور تمہیں بھی ہمارے ساتھ پیار ہے
لیکن تمہاری ترقی کا میدان کھلنے کے لئے ضروری ہے کہ جب ہم اپنا وقت پورا کر چکیں تو ہم
چلے جائیں اور تم ہماری جگہ لو.وہ وقت بے شک صدمہ کا وقت ہوگا لیکن ہمیں کوشش کرنی
چاہیے کہ ہم اس صدمہ کو اسی طرح برداشت کریں جس طرح اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے.جانیوالا اپنے مولیٰ سے راضی ہو کر اس کے حضور پہنچنے کی تیاری کرے اور پیچھے رہنے والے بھی
اپنے مولیٰ کی رضا کو خوشی خوشی قبول کریں.کیونکہ اگر چہ انسانوں پر موت آتی ہے اور ہم اپنے
والدین اور اپنے دیگر بزرگوں اور عزیزوں سے جدا ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ حستی وقیوم ہے
اور اس پر موت نہیں آتی اور وہی ہم سب کا آتا ہے اور ہم سب اسی کے بندے ہیں اور اسی
کے حضور ہم سب کو جمع ہونا ہے.اور ایک سچے مومن پر تو جب وہ وقت آتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ
سے رحمت کی امید کرتا ہو ا شوق سے اپنے مولیٰ کے حضور حاضر ہونے کے لئے تیار ہو جاتا
ہے.رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے اپنی موت سے تھوڑا عرصہ قبل فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے
ایک بندہ کو یہ اختیار دیا کہ وہ اس دنیا میں رہے یا اللہ تعالیٰ کے حضور چلا جائے تو اس نے
137
Page 138
آخری بات پسند کی.اس پر حضرت ابو بکر رو پڑے باقی صحابہ نے بعد میں محسوس کیا حضرت
ابو بکر اس وقت سمجھ گئے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ جس کا ذکر حضور نے فرمایا تھا وہ خود حضور ہی
تھے.اور میں نے اپنی والدہ مرحومہ سے متعلق خود دیکھا کہ وہ نہایت اطمینان سے اور خوشی
خوشی ہم سے رخصت ہوئیں اور ہمیں صبر کی تلقین کی اور پھر اپنے مولیٰ کی طرف رُخ کر لیا اور
ہم سے جُدائی کا خیال اس طرح دل سے نکال دیا کہ گویا جدائی کا انہیں کوئی احساس ہی نہیں
اور یہ وہی ماں تھی جسے ایک لمحہ بھر کی جدائی ہم سے گوارا نہ تھی.گواُن کی وفات سے کچھ عرصہ
پہلے جب انکی یہ حالت ہوگئی تو میرا دل آنے والی جدائی کو محسوس کر کے اس بات سے بھی
تکلیف محسوس کرتا تھا کہ ان کی توجہ ہماری طرف اب نہیں لیکن اس خیال سے ایک اطمینان
بھی محسوس کرتا تھا کہ ایک مومن کی یہی حالت ہونی چاہیے جو اس وقت میری والدہ کی تھی
کیونکہ موت کے خیال سے انہیں کوئی تشویش یا گھبراہٹ نہ تھی اور وہ اپنے مولیٰ کے حضور
جانے پر راضی اور خوش تھیں.دعا ہے کہ میرا وقت آنے پر اللہ تعالیٰ اپنے رحم سے میرے دل
کی بھی یہی حالت کر دے اور مجھے ایسی حالت میں موت دے کہ وہ خود مجھ سے راضی ہو اور
اس کی رحمت کے دروازے میرے لئے کھلے ہوئے ہوں.آمین
میں بیان کر چکا ہوں کہ جسم اور رُوح میں کس قسم کا رشتہ ہے.یہ رشتہ انہیں حالات
کے لئے موزوں ہے جو ہمیں اس زندگی میں پیش آتے ہیں اور ان حالات کے مطابق روح
اس جسم کی مدد سے ترقی کرتی چلی جاتی ہے.لیکن ایک وقت آتا ہے کہ روح موجودہ زندگی
کے حالات میں مزید ترقی نہیں کر سکتی اور اس کی مزید ترقی کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ وہ ایک
اور عالم میں داخل ہو جہاں کے حالات اس زندگی کے حالات سے بالکل مختلف ہیں اور اس
زندگی میں داخل ہونے کے لئے یہ لازم آتا ہے کہ اس جسم کے ساتھ روح کا رشتہ منقطع کیا
جائے.اگر ایسانہ ہو تو انسانی روح کی مزید ترقی رُک جائے گی.اور چونکہ موت کے ذریعہ
انسانی روح ایسے حالات سے نجات پاتی ہے جو اس کی مزید ترقی میں روک ہیں اور ایسے عالم
138
Page 139
میں داخل ہوتی ہے جہاں نئی ترقیوں کے میدان اس کے لئے کھلتے ہیں اس لئے موت مرنے
والے کے لئے بھی رحمت ہے.حالات بعد الموت
مابعد الموت کے حالات کوئی شخص اپنے مشاہدہ یا تجربہ کی بناء پر تو بیان کر نہیں سکتا.کیونکہ ان حالات کا مشاہدہ یا تجربہ موت کے بعد ہی ہو سکتا ہے.اور موت کا دروازہ ایسا
دروازہ ہے جو صرف اندر کی طرف ہی کھلتا ہے باہر کی طرف نہیں کھلتا اور جب کوئی انسان اس
میں سے گزر چکتا ہے تو پھر اس دنیا کی طرف واپس نہیں لوٹ سکتا.اس لئے یہ حالات ہم
تجربہ کی بناء پر نہیں بلکہ اسلام کی تعلیم ہی سے اخذ کر سکتے ہیں.لیکن چونکہ ہم اس تعلیم سے
متعلق اس وثوق اور یقین پر پہنچ چکے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو عالم الغیب ہے
اس لئے ہم اس کے اُس حصہ کو بھی اسی اطمینان اور یقین سے قبول کر سکتے ہیں جس اطمینان
اور یقین کے ساتھ ہم اس کے باقی حصوں
کو قبول کرتے ہیں.حیات بعد الموت کی حقیقت یہ ہے کہ اس زندگی میں ہمارے خیالات اور اعمال کا اثر
ہماری روح پر پڑتا ہے اور ان خیالات اور اعمال کے نتیجہ میں ہماری رُوحانی طاقتوں اور قومی
کانشو نما ہوتا ہے یا ان میں کمزوری یا نقص یا بیماری پیدا ہوتی ہے.ہر انسان کی موت کے
وقت اس کے روحانی قومی اس کی اس زندگی کے حالات کے مطابق ترقی کر چکے ہوتے ہیں.بعض ترقی کے کمال کو پہنچ چکے ہوتے ہیں بعض نے اس سے کم ترقی کی ہوتی ہے بعض میں کوئی
نقص یا بیماری پیدا ہو چکی ہوتی ہے.اس حالت میں روح ایک نئے لطیف عالم میں داخل
ہوتی ہے لیکن اول اول اس عالم میں ایک ایسی بے خبری کی حالت میں داخل ہوتی ہے جیسی
حالت ایک بچہ کی اس دنیا میں پیدا ہوتے ہی ہوتی ہے.اس لطیف عالم کے حالات کے
مطابق روح کے اندر ویسے ہی احساس اور قومی اور طاقتیں ہوتی ہیں جیسے اس دنیا کے حالات
139
Page 140
کے مطابق انسانی جسم میں بچہ کی پیدائش کے وقت ہوتی ہیں.اور روح اس عالم کے حالات
کا ویسے ہی احساس رکھتی ہے اور تجربہ اور مشاہدہ کرتی ہے جیسے جسم اس دُنیا میں کرتا ہے.اور
روح کے اندر اس عالم میں ایک اور عطر یا نچوڑ پیدا ہو جاتا ہے اور وہاں پھر ایک جسم اور رُوح
کا رشتہ پیدا ہو جاتا ہے اور جو یہاں روح تھی وہ وہاں بمنزلہ جسم کے ہوتی ہے گو اس کے
احساس اور قومی وہاں کے حالات کے مطابق ہوتے ہیں اور اس جسم کے اندر جو ایک رُوحانی
جسم ہوتا ہے ایک اور لطیف در لطیف روح پیدا ہو جاتی ہے.اور یہ جسم اور روح کا مجموعہ وہاں
کے لطیف اور روحانی حالات کو ویسے ہی محسوس کرتا ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ تیزی سے محسوس
کرتا ہے جیسے کہ ہمارا موجودہ جسم اس زندگی کی کیفیات کو محسوس کرتا ہے اور اس طرح اس
روحانی عالم میں انسانی روح کی نئی زندگی کا دور شروع ہوتا ہے.اور اس زندگی میں پھر آگے
لا انتہا میدان ترقی کا ہے گو اس کے حالات اور اس کی کیفیات ایسی ہیں کہ ہم ان کا اپنی
موجودہ طاقتوں اور قومی کے لحاظ سے پورا پورا اندازہ نہیں لگا سکتے.اب جیسا کہ میں نے کہا ہے بعض ارواح موت کے بعد کی زندگی کو ایسی حالت میں
شروع کرتی ہیں کہ وہ یہاں سے اپنے قومی کو کمال تک پہنچا کر اس زندگی میں داخل ہوتی ہیں
اور بعض اس سے کم حالت سے اور بعض ایسی حالت سے کہ ان کے اکثر قومی مریض ہوچکے
ہوتے ہیں.جو ارواح کامل صحت اور کامل نشونما کی حالت سے اس زندگی کی ابتداء کرتی ہیں
وہ تو شروع سے ہی خوشی کی حالت میں رہتی ہیں.اور ان کی ترقی ابتداء سے ہی شروع ہوتی
ہے اور ان کا نور جلد جلد بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے قرب کی منازل سُرعت
سے طے کرنا شروع کر دیتی ہیں.لیکن جن ارواح میں کوئی نقص یا عیب یا کمزوری یا نقص یا
بیماری ہوتی ہے ان کو پہلے ایسے حالات میں سے گزرنا پڑتا ہے جن کے نتیجہ میں ان کے عیب
یا کمزوری یا نقص یا بیماری کی اصلاح کی جائے اور وہی حالات اور کیفیات جو کامل ارواح کے
لئے ایک لذیذ خوشی کا باعث ہوتے ہیں اور انہیں سرور میں ڈال دیتے ہیں.وہ ناقص ارواح
کے لئے ان کے نقص یا بیماری کی نوع اور درجہ کے مطابق تکلیف دہ ثابت ہوتے ہیں لیکن
140
Page 141
جوں جوں ان کے نقص یا بیماری کی اصلاح ہوتی جاتی ہے ان کی تکلیف کم ہوتی جاتی ہے.اور
جب وہ پوری صحت کو پہنچ جاتے ہیں تو وہی حالات اور کیفیات ان کے لئے بھی خوشی اور سرور
کا باعث بن جاتے ہیں.اس کیفیت کو ذہن نشین کرنے کے لئے یوں مثال پیش کی جاسکتی ہے کہ اگر ایک شخص
کی آنکھ میں کوئی نقص ہو جس سے اس کی آنکھ دُکھنے آگئی ہو تو سورج کی روشنی اس کے لئے
سخت دُکھ اور تکلیف کا باعث ہوتی ہے اور اسے کچھ عرصہ اندھیرے میں رہنا پڑتا ہے اور وہ
سورج کی روشنی سے فائدہ حاصل کرنے یا حظ اٹھانے کے قابل اس وقت ہوتا ہے جب اس
کی آنکھ کی پوری اصلاح ہو جائے اور ایسی حالت میں اس کے لئے سب سے زیادہ تکلیف
اور عذاب یہی ہے کہ اُسے روشنی میں بسر کرنا پڑے.اس کے مقابلہ میں وہ شخص جس کی آنکھ
صحت کی حالت میں ہو اور جس کی بینائی اپنی پوری طاقت رکھتی ہو وہ سورج کی روشنی سے
خوب فائدہ اٹھاتا ہے اور خوبصورت منظر دیکھ کر خوش ہوتا ہے اور اسے چلنے پھرنے میں آسانی
ہوتی ہے اور وہ لکھ پڑھ سکتا ہے.غرض وہ اپنا تمام کاروبار سہولت سے کر سکتا ہے اور کئی قسم کی
راحتیں اور آرام اسے روشنی کی وجہ سے حاصل ہوتے ہیں اور روشنی سے محروم کر دیا جانا اس
کے لئے عذاب ہو جاتا ہے.حالانکہ یہ وہی روشنی ہے جو اس دوسرے شخص کے لئے دکھ اور
تکلیف کا موجب ہے.اور یہی حال باقی قویٰ کا بھی ہے.مثلاً ایک شخص کی زبان پر زخم ہو گیا
ہو اور اسے نمک مرچ اور مصالحہ کے ساتھ تیار کئے ہوئے عمدہ عمدہ کھانے کھلائے جائیں تو وہ
اس کے لئے سخت دُکھ کا موجب ہونگے اور اس سخت دکھ کی حالت میں وہ پکار پکار کر التجا
کرے گا کہ یہ عذاب مجھ سے دُور کیا جائے حالانکہ ایک شخص جس کی زبان اپنی پوری صحت کی
حالت میں ہو وہ ان کھانوں کو بڑے مزے سے کھائیگا اور ان سے لذت حاصل کر یگا اور انہیں
ایک نعمت سمجھے گا.البتہ بیمار شخص کی زبان جوں جوں صحتیاب ہوتی جائیگی ایسے کھانے اس
کے لئے کم تکلیف کا موجب ہونگے اور پوری صحت حاصل ہو جانے پر وہ بھی انہیں لذیذ
محسوس کرنے لگے گا.141
Page 142
یہی کیفیت آئندہ زندگی میں روح کی ہوگی.جن ارواح کی استعدادوں میں نقص
واقع ہو چکا ہوگا انہیں ایک عرصہ ایسے حالات میں رہنا پڑے گا جن میں انکی کمزوریوں اور
عیوب اور امراض کی اصلاح کی جائینگی.گویا انہیں ایک قسم کے ہسپتال میں گذرنا ہوگا اور اپنی
اپنی بیماری کے مطابق یہ حالت ان کے لئے تکلیف دہ ہوگی لیکن اصلاح کی تکمیل ہو جانے پر
ہر ایک رُوح اس عالم کی کیفیات کے مطابق ترقی کرنا شروع کر دے گی.یہ مثال صرف کیفیات کا کسی قدر اندازہ کرنے کے لئے ہے ورنہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ ایک ایسی زندگی ہے کہ اس کی کیفیات نہ انسانی آنکھوں
نے دیکھیں اور نہ انسانی کانوں نے سنیں اور نہ کسی بشر کے دل میں ان
کا پورا تخیل آسکتا ہے
بلکہ اس عالم میں جو ترقیات ممکن ہیں وہ زیادہ تر نور اور قرب الہی کی اصطلاحات میں بیان کی
گئی ہیں.کتب برائے مطالعہ
یہ ایک نہایت ہی مختصر خا کہ اس تعلیم کے بعض پہلوؤں کا ہے جو ہمیں اسلام احمد یہ
کی تشریح کے مطابق زندگی کے مختلف شعبوں سے متعلق دیتا ہے.اس خا کہ کے پیش کرنے
سے میری اغراض یہ ہیں کہ اول تو تمہیں اسلامی تعلیم سے دلچسپی پیدا ہو اور جب تمہیں یہ معلوم
ہو جائے کہ اس تعلیم کے اندر کس قدر خزانے مخفی ہیں تو تم اس مختصر سی تمہید کے نتیجہ میں خود
اسلامی تعلیم کے مختلف پہلوؤں کا مطالعہ کرو.اس مطالعہ کی ترتیب یہ ہونی چاہیے کہ اول تو تم
قرآن کریم کو باترجمہ پڑھنا شروع کر دو اور اس اس کے بعد اس کا مطالعہ متواتر جاری رکھو
کیونکہ اس کے اندر نہ ختم ہو نیوالے علمی اور روحانی خزانے ہیں اور ان کے گہرے مطالعہ کی
عادت ڈالو.جتنا تم اس کا مطالعہ کرو گے اتنا ہی تمہارا علم وسیع ہوتا چلا جائے گا.پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ و السلام کی تصانیف میں سے کم سے کم ذیل کی
142
Page 143
تصانیف کا تمہیں ضرور مطالعہ کرنا چاہیے.اور اگر میسر آئے تو تمام تصانیف کم سے کم ایک بار
تو جہ سے پڑھ لینی چاہئیں.ا.اسلامی اصول کی فلاسفی ۲ کشتی نوح ۳.براہین احمدیہ پانچوں حصے
۴- ازالہ اوہام ۵- آئینہ کمالات اسلام تریاق القلوب
۷.چشمہ معرفت - تحفہ گولڑو یہ.نزول ایح ۱۰.حقیقۃ الوحی
حضرت خلیفتہ امسیح الاوّل کی تصانیف میں سے فصل الخطاب اور نور الدین اور حضرت
خلیفہ اسیح الثانی کی تصانیف میں سے احمدیت یعنی حقیقی اسلام اور دعوۃ الا میر اور تمام جلسوں
کی تقریریں.اور اگر پچھلے خطبات میسر آجائیں تو وہ بھی سب ورنہ یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ
آئندہ ہمیشہ خطبہ جمعہ توجہ سے پڑھ لیا کرو.رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوانح کا مطالعہ بھی ضروری ہے جس کے لئے سیرت
النتبين مصنفہ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نہایت موزوں ہے.اس کی ابھی دوجلدیں
چھپی ہیں لیکن انشاء اللہ تیسری جلد بھی جلد چھپ جائے گی اور امید ہے کہ یہ تصنیف تین
خاتم "
جلدوں میں ختم ہو جائے گی.احادیث صحیحہ کے مختلف مجموعوں میں سے کم سے کم صحیح بخاری کو پڑھ لینا چاہیے.لیکن
اس کی ابتداء کرنے سے پہلے ریاض الصالحین جو احادیث کا ایک مختصر مجموعہ ہے اور با ترجمہ
چھپ چکی ہے پڑھ لینی چاہیے.اردو میں بھی بعض مختصر مجموعے چھپے ہیں اور حضرت میر محمد
اسحاق صاحب نے بھی ایک مختصر مجموعہ احادیث بنام اسوہ حسنہ چھپوایا ہے.حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے سوانح اور سیرت سے بھی واقفیت حاصل
کرنی چاہیے.ایک مختصر سی سیرت حضرت خلیفہ اسیح الثانی کی تصنیف بھی ہے اور پھر
سیرت المہدی مرتبہ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب کی تین جلدیں چھپ چکی ہیں جو حضرت
مسیح موعود سے متعلق روایات کا مجموعہ ہیں، ان کا مطالعہ بھی مفید ہے.حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ و السلام کے الہامات، کشوف اور رؤیا کا مجموعہ بنام
143
Page 144
تذکرہ چھپ چکا ہے اسے بھی ضرور زیر مطالعہ رکھنا چاہیے.سلسلہ احمدیہ کی مختصر تاریخ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب تیار کر رہے ہیں.یہ رسالہ
بنام سلسلہ احمدیہ انشاء اللہ دورانِ سال میں چھپ جائیگا اس کا بھی ضرور مطالعہ کرنا چاہیے.اگر تم کم سے کم استقدر مطالعہ آئندہ دو تین سال میں پورا کر لوتو اول تو تمہیں اسلام اور
احمدیت کی تعلیم اور تاریخ سے واقفیت ہو جائیگی دوسرے تمہیں یہ بھی معلوم ہو جائیگا کہ اسلام تم
سے اس زمانہ میں کیا چاہتا ہے اور تم اپنے فرائض حقیقی سے واقف ہو جاؤ گے.پھر میری دوسری غرض کی تکمیل خود بخو د شروع ہو جائے گی اور وہ یہ کہ تم جو ہمارے
عزیزوں میں آئندہ نسل اور پور میں سب سے بڑے ہو جب تم اپنی ذمہ داریوں کو اچھی طرح
سمجھ لو گے اور انہیں پورے طور پر ادا کرنا شروع کر دو گے تو مجھے یہ اطمینان ہو جائیگا کہ جس
ذمہ دار کو ہم نے اپنے میلی ہے اس ہاری آمد وسل پورے طور پر بھی ہے اوراسے
ذمہ آئندہ
پورے طور پر ادا کرنیکی کوشش کرے گی.میں نے یہ تحریر جلد جلد قلم برداشت لکھی ہے اس میں کئی جگہ غلطیاں بھی رہ گئی ہونگی اور
بعض مقامات پر شاید مطلب بھی پورے طور پر ادا نہ ہوا ہو.اگر تم اسے توجہ سے پڑھو اور
جہاں مطلب صاف نہ ہو مجھ سے دریافت کر لو اور پھر صحیح مطلب کو ذہن نشین کرنیکی کوشش کرو
تو انشاء اللہ تمہیں اس سے بہت مدد ملے گی اور بہت سی ذہنی کاوش سے تم بچ جاؤ گے اور اپنی
اپنی دینی اور اخلاقی تربیت صحیح اصولوں کی بناء پر کر سکو گے.اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے پورا فائدہ
اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اور وہ غرض پوری کرے جس غرض سے میں نے یہ تحریر لکھی ہے
اور اگر اس میں کوئی ایسی بات بیان ہوئی ہو جس میں کوئی خامی یا نقص رہ گیا ہے یا وہ اسلامی
تعلیم کی روح کے مطابق نہیں تو اللہ تعالیٰ میری غلطی کو معاف فرمائے اور اس نقص کے اثر سے
تمہیں محفوظ رکھے.آمین
والسلام
خاکسار ظفر اللہ خان.شملہ 31 مئی 1939ء
144