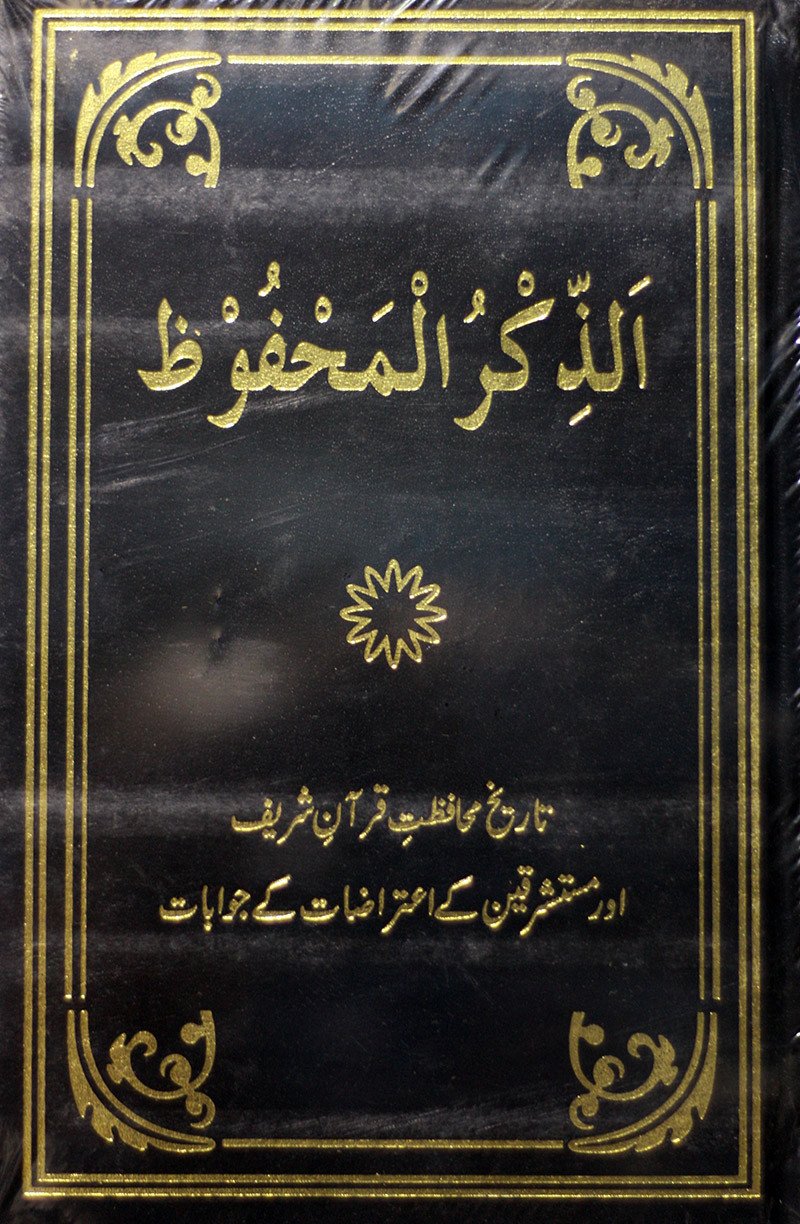Complete Text of Al-Zikrul Mahfooz
Content sourced fromAlislam.org
Page 1
إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحْفِظُوْنَ
اس نے اس وعدہ کے موافق اپنے ذکر کی محافظت فرمائی اور مجھے مبعوث کیا
امام الزماں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی معہود علیہ السلام
اَلذِكُرُ الْمَحْفُوظ
تاریخ محافظت قرآن شریف کے
اور مستشرقین کے اعتراضات کے جوابات کے
Page 3
:=
نمبر شمار
1 - اظہار تشکر
2 پیش لفظ
3.فہرست عناوین
فہرست موضوعات
4 باب قرآن کریم کی لفظی محافظت
فصل عہد نبوی میں جمع و تدوین قرآن
پندرہ (15) ذیلی عناوین
فصاح عہد خلافت راشدہ میں جمع و تدوین قرآن کریم
چار (4) ذیلی عناوین
صفحه
<
vii
xiv
1
12
77
5 با تحریف قرآن کے ضمن میں لگائے جانے والے الزامات کے جوابات 103
-6
-7
پچاس (50) ذیلی عناوین
با قرآنِ کریم کی معنوی محافظت
انڈیکس
انڈیکس آیات قرآن کریم
انڈیکس اعتراضات
انڈیکس اسماء
پانچ (5) ذیلی عناوین
365
399
--
i
<
vii
Page 5
اظہار تشکر
الحمد لله ذو المنن
رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَ عَلَى وَالِدَيَّ أَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً
تَرْضَهُ وَ اَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّلِحِينَ
خاکسار کو تفسیر القرآن میں تخصص کے دوران مستشرقین کے حفاظت قرآن کے موضوع پر اعتراضات
کے جواب کے موضوع پر مقالہ لکھنے کا کام تفویض ہوا تھا.مقالہ نگران مکرم و محترم جناب چوہدری محمد علی صاحب
تھے جن کے سایہ شفقت میں اور دعاؤں سے تمام مراحل آسان ثابت ہوئے.اسی مقالہ کو نظر ثانی اور
بہت سی تبدیلیوں اور اصلاحات کے بعد کتابی صورت میں پیش کرنے کی توفیق پا رہا ہوں.خاکسار مکرم و محترم حضرت صاحبزادہ مرزا حنیف احمد صاحب مد ظلہ العالی کی ہمہ وقت اور شفقت سے
بھر پورراہنمائی پر ہر وقت اُن
کا ممنونِ احسان ہے.اسی طرح خاکسار مکرم و محترم جناب سید عبدالحی شاہ صاحب ناظر اشاعت ربوہ کا بھی تہہ دل سے مشکور
ہے جو ہمیشہ اپنی گوں ناگوں مصروفیات کے باوجود ہمیشہ خاکسار کی وقت بے وقت حاضری کو فراخدلی سے
معاف فرماتے ہیں.آپ نے اپنے انتہائی قیمتی اوقات سے میں سے ناچیز کی اس حقیر سی کوشش کو بھی وقت دیا
اور مطالعہ کر کے شائع کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی.میرے مشفق استاد مکرم ومحترم جناب خواجہ ایاز احمد صاحب کی راہنمائی ہمیشہ شاملِ حال رہی.مقالہ لکھنے
کے دوران جب ضرورت پڑی خاکسار نے اُن کی شفقت کی وجہ سے بلا جھجک اُن سے راہنمائی حاصل کی.خاکسار خاص طور پر محترم محمد مقصود احمد منیب صاحب مربی سلسلہ کا ہمیشہ ممنونِ احسان رہے گا جنہوں
نے بھر پور توجہ اور محنت سے نظر ثانی کی اور لغوی اعتبار سے بہت سی مفید اصلاحات کیں.جزاہ اللہ خیراً
مکرم ظہور الہی تو قیر صاحب مربی سلسلہ اور مکرم را شد محمود احمد صاحب مربی سلسلہ کی بے لوث مدد پر
خاکسار ان دونوں احباب کا تہہ دل سے ممنون ہے.خاکسار محترم نصیر احمد قمر صاحب مربی سلسلہ ایڈیشنل وکیل الاشاعت لنڈن وایڈیٹر الفضل انٹرنیشنل کا
تہہ دل سے مشکور ہے جن کی پر خلوص اور بے لوث مدد اور رہنمائی سے آخری مراحل بھی طے ہوئے.میرے مولی کا کتنا بڑا فضل ہے کہ اس کے پاک مسیح کی پیاری جماعت کا ہر وہ فرد جس کی جب بھی
ضرورت پڑی میرے جیسے کمزور اور حقیر انسان کی امداد کو موجود تھا.میرے مولیٰ تو ان سب احباب کو
بہترین جزاء دے.ان سب نے محض تیری رضا کی خاطر ایک نا چیز حقیر اور کمزور انسان کی بے لوث امداد
اور رہنمائی کی.تو بھی ان کا مددگار اور راہنما ہو جا.اورسب سے بڑھ کر اندھی عقلوں کو انوار الہی سے منور کرنے والی وہ آسمانی ہدایت اور راہنمائی ہے جو
آج کے دور میں مہدی دوران اور اُن کے خلفاء کی صورت میں ہمیں فیضیاب کر رہی ہے.کس طرح تیرا کروں اے ذوالمنن شکر و سپاس
وہ زباں لاؤں کہاں سے جس سے ہو یہ کاروبار
Page 7
vii
پیش لفظ
رب انفخ روح بركة في كلامي هذا واجعل افئدة من الناس تهوى اليه
اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے:
إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِكْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ (الحجر: 10)
یعنی یقیناً ہم ہی نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں
یہ آیت اسلام کی صداقت کا ایک عظیم الشان ثبوت ہے اور اگر کوئی تعصب سے پاک انسان اس آیت پر غور
کرے تو سمجھ سکتا ہے کہ یہ دعویٰ انسانی نہیں.تمام مفسر ، جدید عرب محققین اور یورپین مصنف بالا تفاق کہتے ہیں
کہ یہ سورۃ مکی ہے.مکی دور مسلمانوں کے لیے ابتلاؤں اور آزمائشوں سے پر ایک ایسا دور تھا کہ مذاہب عالم میں
اس کی مثال نہیں ملتی.ابتدائی مومنین اسلام قبول کرنے کی پاداش میں انسانیت سوز مظالم کے شکار ہورہے تھے.تھوڑے سے تو مسلمان تھے جن میں سے کچھ جلتے سورج تلے تپتی ریت پر بھاری بوجھوں کے تلے سسک رہے
تھے تو کچھ نگی پیٹھوں پر لیٹے اپنی پچھلتی چربیوں سے دہکتے کوئلوں کی پیاس بجھا رہے تھے.ایک طرف سے آل
یا سر کی آہ و بکا ابھرتی تھی تو دوسری طرف وہ مقدس بدن دہائی دے رہے ہوتے جنہیں دو اونٹوں سے باندھ کر پھر
اُن اونٹوں کو مخالف سمت میں دوڑا کر چیر دیا گیا تھا.مسلمان ہونے والوں کو بے تحاشاز دوکوب کیا جاتا اور جب
ظالم مار مار کر خود ہی تھک جاتے تو زخموں سے چور اور در دوالم سے بے حال ان غریبوں کے گلوں میں رستے ڈال
کر لا ابالی نوجوانوں کے سپر د کر دیا جاتا جو انہیں مکہ کی سنگلاخ گلیوں میں گھسٹتے پھرتے.چٹائیوں میں لپیٹ کر
ناک میں دھونی دی جاتی اور اس اذیت ناک انداز میں دم گھونٹا جاتا.اُن ستم رسیدہ مسلمانوں کی آہ وزاری سے
پتھر دل پگھل کیوں نہ گئے !!! عصمت تاب مسلمان خواتین مخالفین کی درندگی کا شکار ہورہی تھیں تو خود سید
المعصومین بھی خون آشام بھیٹریوں کے ظلم و ستم کا شکار تھے.آہ! کیوں اُس پیارے چہرے کو لہولہان کیا گیا !!! آہ
! بنی نوع انسان کے غم میں تڑپنے والے اور اپنی جان سے زیادہ نوع انسانی سے پیار کرنے والے کو کیوں ستایا
گیا !!! بخاری میں روایت ہے:
حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ میں نے آنحضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کوکسی نبی کی
حکایت فرماتے ہوئے دیکھا.جس کو اس کی قوم نے لہو لہان کر دیا تھا.اور وہ اپنے چہرے سے خون
پونچھتے جاتے تھے اور دعا کرتے جاتے تھے کہ اے خدا! میری قوم کو بخش دے.وہ نادان ہے.(بخاری استابة المرتدين باب اذا عرض الذي........
Page 8
الذكر المحفوظ
viii
پھر مکی زندگی کے آخری سال بھی نہایت ہی خطر ناک تھے.آنحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم اپنے ساتھیوں
سمیت شعب ابی طالب میں محبوس تھے.شاہ دو جہاں اور اس کے پیارے جانثار بھوک و افلاس کا شکار تھے.وہ
دور تھا کہ کفار مکہ کا بچہ بچہ مسلمانوں کا جانی دشمن بن چکا تھا اور مسلمانوں کو اپنی حفاظت کے لیے جگہ نہ ملتی تھی.ایسے پر آشوب وقت میں جب کہ مسلمان کمزوری اور کسمپرسی کی حالت میں مخالفین کی مشق ستم تھے، اللہ تعالیٰ کا یہ
فرمانا کہ ہم خود قر آن کریم اور اس کی تعلیم کی حفاظت کریں گے کتنا زور دار اور پر شوکت دعویٰ ہے.اس فقرہ (انا
نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحفِظون ) کی طاقت کو وہی لوگ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں جو عربی جانتے ہیں.کیا یہ عجیب بات نہیں کہ جب مسلمان خود مخالفین کے گھیرے میں تھے اور ان کو جان کے لالے پڑے ہوئے
تھے.کفار کے مظالم نے ابتدائی مسلمانوں کو منتشر کر رکھا تھا اور ان کی زندگی میں کوئی اجتماعیت نہ تھی.مخالفین سمجھتے
تھے کہ جولوگ اپنی حفاظت نہیں کر سکتے اور ہمارے رحم و کرم پر ہیں ہم ان کو اور اس تعلیم کو جس پر ایمان لانے کے
یہ دعویدار ہیں جب چاہیں صفحہ ہستی سے مٹادیں گے.ایسے میں مخالفین کول کارا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ تم سارا
زور لگا لو اور قرآن مجید کے مٹانے کے لیے پوری طاقت خرچ کر دو تو بھی تم نا کام رہو گے کیونکہ ہم خود اس کی
حفاظت کریں گے.پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ تمام تر مخالفتوں کے باوجود آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اور آپ کے ساتھی آزاد ہوتے اور ترقی پاتے ہیں.ایک عظیم الشان جماعت آپ کے ساتھ ہو جاتی اور قرآن
مجید کی کمانہ حفاظت ہوتی ہے اور آج تک ہورہی ہے اور ہوتی رہے گی.کیا یہ بے نظیر حفاظت دنیا کی اور کسی
مذہبی کتاب کو حاصل ہوئی ہے؟ ریورنڈ باسورتھ سمتھ رقم طراز ہیں:
In the Quran we have, beyond all reasonable doubt,
the exact words of Muhammed without subtraction
and without addition
(R.Basworth Smith"Mohammad and Mohammadanism".London
1874, p.15)
آج ہمارے پاس موجود قرآن کریم میں بلاشک و شبہ کسی بھی قسم کی کمی بیشی کے بغیر محمد
(ع) کے ہی الفاظ ہیں.ویلیئم میور اپنی کتاب لائف آف محمد کے دیباچہ میں بحث کے بعد لکھتا ہے."We may upon the strongest presumption affirm that
every verse in the Coran is genuine and unaltered
composition of Muhammad himself."
ترجمہ.ہم نہایت مضبوط قیاسات کی بنیاد پر کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کریم کی ہر ایک آیت اصلی
ہے اور ہر قسم کی تحریف سے پاک محمد ( آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ) کی ہی تصنیف ہے.
Page 9
ix
پھر لکھتا ہے:."And conclude with at least a close approximation to
the verdict of Van Hammer that we hold the Coran to be
as surely Muhammad's words as the Muhammad held it
to be the word of God."
(William Muir, Life of Mohamet, London, 1894, Vol.1,
Introduction)
ہم وان ہیمر کے مندرجہ ذیل فیصلہ کے بالکل مطابق نہ سہی کم سے کم اس کے خیال کے بہت
موافق فیصلہ تک پہنچتے ہیں.وان ہیمر کا فیصلہ یہ ہے کہ اس زمانہ میں جو قرآن موجود ہے اس کے
متعلق ہم ویسے ہی یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ اصلی صورت میں محمد ( رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم) کا بنایا ہوا کلام ہے.جس یقین سے کہ مسلمان کہتے ہیں کہ وہ خدا کا غیر مبدل کلام ہے.نولڈ کے کا قول ہے:
"Slight clerical errors there may have been, but the
Qur'an of Othman contains none genuine element,
though sometimes in very strange order.Efforts of
European scholars to prove the existence of later
interpolations in the Qur'an have faild."
(Encyclopedia Britanica Edition 11 under Heading "Quran")
ممکن ہے کہ تحریر کی کوئی معمولی غلطیاں ( طرز تحریر ) ہوں تو ہوں.لیکن جو قرآن عثمان نے
دنیا کے سامنے پیش کیا تھا اس میں کچھ بھی بیرونی آمیزش نہیں ہے.گو اس کی ترتیب عجیب ہے.یورپین علما کی یہ کوششیں کہ وہ ثابت کریں کہ قرآن میں بعد کے زمانہ میں بھی کوئی تبدیلی ہوئی
ہے بالکل ناکام ثابت ہوئی ہیں.یہ وہ شہادتیں ہیں جو اسلام کے شدید ترین دشمنوں کی ہیں.اَلْفَصْلِ مَا شَهِدَ بِهِ الْأَعْدَاءَ
مگر با وجود اس واضح ثبوت کے دشمنانِ اسلام تعصب میں اندھے ہو کر اس حصن حصین کی دیواروں سے سر
ٹکراتے چلے آئے ہیں کہ کسی طرح یہ ثابت کر دیا جائے کہ قرآن کریم بھی دوسرے مذاہب کی کتب کی طرح
انسانی دست برد کا شکار ہو چکا ہے.ہر دور میں مخالفوں نے ہر ممکن کوشش کی اور زور لگایا اور ہر جائز وناجائز تدبیر کو
آزمایا مگر ہمیشہ ناکامی اور نامرادی کا طوق گلے کا ہار بنا.آج بھی شیطان کے چیلے اپنا زور لگا رہے ہیں اور آئندہ
بھی لگاتے چلے جائیں گے
مگر بدنصیبی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہو گا.آئندہ سطور میں ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے کہ کس طرح اور کن ذرائع سے خدا تعالیٰ اپنے کلام کی
حفاظت کا وعدہ پورا کرتا چلا آرہا ہے اور کیا دلائل ہیں کہ آئندہ بھی حفاظت کا وعدہ پورا کرتا رہے گا.اس کے ساتھ
Page 10
الذكر المحفوظ
X
ساتھ ہم دشمنان اسلام کے ان وساوس کا جواب بھی ڈھونڈیں گے جو وہ اس کی حفاظت کے موضوع پر عام قاری
کے دل میں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں.زیر نظر کاوش میں حفاظت قرآن کے ذرائع کے مطالعہ کے ساتھ ساتھ اس موضوع پر اُٹھنے والے اہم
سوالات اور دانستہ طور پر نا واقف لوگوں کے دلوں میں پیدا کیے جانے والے شبہات کے ازالہ کو بھی مدنظر رکھا گیا
ہے اور اس ضمن میں 1995 میں سامنے آنے والی ایک گمنام معترض کی کتاب WHY I AM NOT A
MUSLIM میں حفاظت قرآن کے موضوع پر اُٹھائے جانے والے بنیادی اعتراضات کو مدنظر رکھا گیا ہے.اس گمنام معترض نے اپنا قلمی نام ابن وراق رکھا ہے.معترض کی کتاب کے ضمن میں یہ عرض کردوں کہ مصنف کے نا معلوم ہونے اور کتاب کے انداز سے یہ
احساس ہوتا ہے کہ ابن وراق ایک خیالی اور تصوراتی شخصیت ہے جبکہ یہ کتاب کسی کمیٹی کی مرتبہ ہے اور عین ممکن
ہے وہ کمیٹی عیسائیوں کی بنائی ہوئی ہو.کیوں کہ کتاب میں زیادہ تر عیسائی مصنفین کے حوالہ سے بات کی گئی ہے.اس پر ایک قرینہ یہ بھی قائم ہوتا ہے کہ حقیقت میں ابن وراق ایک مسلمان محقق اور عالم تھے جو کہ نویں صدی میں
پیدا ہوئے اور انہوں نے عیسائیت پر گراں قدر علمی کام کیا اور عیسائیت کے عقائد کی حقیقت ظاہر کی.شائد اسی
تعلق میں آج ابن وراق کے نام سے ایک خیالی پتلا گھڑا گیا ہے (واللہ اعلم ) لیکن اس کوشش میں کتاب میں
حقائق کے نام پر باتیں بھی خیالی ہی پیش کر دی گئی ہیں جن کا حقیقت سے دور کا بھی تعلق نہیں.یہ انداز نیا نہیں.متعصب دشمن اسلام دشمنی میں ایسے ہتھکنڈے بہت پہلے سے ہی اختیار کرتے آئے ہیں.اہل اسلام ہر زمانہ میں ایسے خناس صفت دشمن کے حملوں کا جواب دیتے رہے ہیں.حضرت مرزا غلام احمد
قادیانی مسیح موعود و مہدی معہود علیہ السلام نے بھی دفاع اسلام میں ایسے دشمنوں کے دانت کھٹے کیے جو چھپ کر
وار کرنا چاہتے تھے.پھر بیسویں صدی کے شروع میں جماعت احمدیہ کی طرف سے دفاع اسلام میں جاری کیے
گئے ایک انقلابی انگریزی رسالہ Review of Religions کے جنوری 1904 کے شمارہ میں بھی ایک گمنام پادری
کے اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے جو چھپ کر اسلام پر حملہ کرتا ہے.پھر اسی رسالہ کے 1907 کے ایک اردو
شمارہ میں بھی ایک ایسے عیسائی کے اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے جو اپنا نام ظاہر کیے بغیر اعتراضات کرتا
ہے.عین ممکن ہے کہ ہر دشمن اسلام جو اسلامی تعلیمات سے آگاہ ہے، جب بھی بے جا بغض اور دشمنی کی راہ
سے اعتراض کرے تو اس کے لیے سب سے آسان یہی راہ ہو کہ اعتراض کرتے ہوئے دُنیا کی نظروں سے خود کو
چھپالے تا کہ اپنے لچر اعتراضات کے جواب کے بعد ملنے والی ذلت اور نکبت سے بچ سکے لیکن خصوصیت سے یہ
مزاج عیسائی معترضین کا ہے اور سورۃ الناس میں درج پیشگوئی مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ہ کی صداقت کا
Page 11
xi
منہ بولتا ثبوت ہے.صرف یہی نہیں بلکہ جس طرح تمام مذاہب کے اہل علم تحقیق و جستجو کے بعد اب یہ تسلیم کرنے
لگے ہیں کہ یہ مذاہب اب اصل پیغام بھلا چکے ہیں اسی طرح دُشمنانِ اسلام چاہتے ہیں کہ اسلام کے بارہ میں بھی
ایسے اہل علم مل جائیں جو یہ ثابت کر دیں کہ اسلام بھی اپنے اصل کو کھو چکا ہے.لیکن جب انہیں ایسے مسلمان علماء نہیں
ملتے تو شکوک پیدا کرنے کے لیے مسلمان کہلانے والوں میں سے ایسے جہلاء کی تلاش میں رہتے ہیں جو اسلامی
تعلیمات سے ناواقف ہوں اور زبان درازی ، بلا ثبوت الزام تراشی اور ہرزہ سرائی میں اُن کے مددگار ہو سکیں.ابن وراق کا تعارف یہ کرایا گیا ہے کہ موصوف جے پورا نڈیا میں پیدا ہوئے اور پھر پاکستان تشریف لے
آئے یہاں سے Scottland تشریف لے گئے اور وہاں کسی یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں.مذہباً مسلمان ہیں اور
شیعہ فرقہ کے کسی مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں.کتاب کے مطالعہ سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہوتی ہے کہ مصنف یا کمیٹی نے مختلف مستشرقین کی کتب
میں سے صرف اعتراضات کو اکٹھا کیا ہے.یہ قلعی بھی کھل جاتی ہے کہ اسلام کے بارہ میں مختلف مستشرقین اور متقین
کی تحقیقات میں سے اپنے مطلب کا حصہ چن لیا گیا اور پورے شد ومد کے ساتھ پیش کیا گیا.جہاں جہاں تبصرہ کیا
ہے وہاں دیانت داری کو بالائے طاق رکھتے ہوئے انتہائی غلط بیانی سے کام لیا گیا ہے.کتاب کے مطالعہ سے یہ
بات عیاں ہوتی ہے کہ مقصد تنقیدی تحقیق نہیں اور نہ ہی حق کی تلاش مقصود ہے بلکہ کتاب کا مقصد عام قاری کو ایسی
بحثوں میں اُلجھانا ہے جن سے وہ شکوک و شبہات کی دلدل میں پھنس کر حق اور سچ کی جستجو سے ہی ہاتھ کھینچ لے.اسلام کے علاوہ تمام دیگر مذاہب کے مطالعہ سے یہ واضح ہوتا ہے کہ تاریخی طور پر بہت کمز ور اور غیر مستند
ہونے کی وجہ سے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور حتمی طور پر کچھ علم نہیں ہوتا کہ اصل تعلیمات کیا تھیں.ہر طرف انسانی دست بُرد کی کارستانیاں ہی نظر آتی ہیں اور غور وفکر کرنے والا قاری شکوک وشبہات کی دلدل میں
گرفتار ہوتا چلا جاتا ہے.اب ایک چالا کی یہ کی جارہی ہے کہ کسی بھی طرح ان شکوک و شبہات کے سیلاب تند کا
رخ اسلام کی طرف موڑ دیا جائے.چنانچہ سادہ لوح لوگوں کو یہ باور کروانے کی کوشش کی جارہی ہے کہ جو
دوسرے مذاہب کا حال ہے وہی اسلام کا حال ہے اس لیے دو ہی راستے ہیں.یا تو اپنے مذہب سے ہی چھٹے رہو
خواہ وہ کیسا ہی ہے کیونکہ اسلام میں بھی تمہیں یہی کچھ ملے گا اور کچھ زیادہ نہیں ملے گا.دوسرا رستہ یہ ہے کہ مذہب
سے ہی کنارہ کش ہو جاؤ.جبکہ حقیقت میں معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے اور اسلام کے معاملہ میں بقول
Bosworth Smith نہ تو کوئی شخص خود کو جل اور فریب میں مبتلا کر سکتا ہے اور نہ کسی اور کو.موجودہ دور میں ایک
یہی مذہب ہے جو بالکل محفوظ ہے اور اسی کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر ہی مقصدِ زیست حاصل کیا جاسکتا ہے.دشمنان اسلام کی یہ کوشش بذات خود اس بات کا ثبوت بھی ہے یہ جنگ بین المذاہب بے شک ہے لیکن اصل
Page 12
الذكر المحفوظ
xii
میں طاغوتی طاقتیں اس کوشش میں ہیں کہ بنی نوع انسان مذہب سے ہی برگشتہ ہو جائے.اس لیے یا تو لوگوں کو
اُن مذاہب کی طرف بلایا جائے جواب اپنے اصل کو کھو چکے ہیں یا پھر اسلام سے بھی دُور کیا جائے.چنانچہ اس
کوشش میں جہاں اسلامی تعلیمات کو بگاڑ کر پیش کیا جاتا ہے وہیں یہ کوشش بھی کی جاتی ہے کہ سادہ لوح لوگ یہ
جھوٹ
بھی تسلیم کرلیں کہ دوسرے مذاہب کی طرح اسلام میں بھی اصل الہی پیغام کے ساتھ لوگوں کی گھڑی ہوئی
کہانیاں خلط ملط ہو چکی ہیں اور دوسرے مذاہب کی طرح اسلام بھی اپنے اصل کو کھو چکا ہے.جبکہ حقیقت اس
کے بالکل برعکس یہی ہے جو Bosworth Smith بیان کرتے ہیں کہ (اسلام کے ) یہاں حقائق ہیں نہ کہ
خیالات اور قیاسات اور ظنون اور طلسماتی کہانیاں.ہم بآسانی معلوم کر سکتے ہیں کہ اصل حقیقت کیا ہے.“
اعتراضات کے جواب میں عام طور پر اعتراض کی نوعیت کے مطابق اور اُٹھائے جانے والے نکات کے
جواب دیے جاتے ہیں اور بلاضرورت تفصیل بیان نہیں کی جاتی.لیکن زیر نظر تصنیف میں اس پہلو کو مدنظر رکھا گیا
ہے کہ چونکہ کتاب 'WHY I AM NOT A MUSLIM‘ کا مقصد شکوک پیدا کرنا ہے نہ کہ تنقیدی تحقیق پیش
کرنا اس لیے اعتراضات کے جواب میں قاری کے ذہن میں پیدا ہونے والے اوہام کے ازالہ کی کوشش کی
جائے چنانچہ مد نظر یہ رہا ہے کہ ابن وراق کے اعتراضات کا جواب اسی صورت میں مکمل ہوگا جبکہ اس کے پیدا
کیے گئے شکوک کا قلع قمع کیا جائے اور حقائق اور دلائل اس طرح عام فہم انداز میں پیش کیے جائیں کہ ان کی روشنی
میں قاری کے دل میں یہ بات راسخ ہو کہ قرآن کریم کامل طور پر ایک محفوظ کتاب ہے.اس وجہ سے مطالعہ کے
دوران شائد یہ احساس ہو کہ جوابات عام نہج سے ہٹ کر کچھ زیادہ تفصیلی ہیں.اگر صرف اعتراضات کے جواب
دینا ہی مدنظر رکھا جائے تو کتاب کا مقصد پورا نہیں ہوگا.مثلاً اگر کسی اعتراض کی بنیا د جھوٹ پر ہے تو اگر اعتراض کا
غلط اور جھوٹ پر مبنی ہونا ہی ثابت کر دیا جائے تو کافی ہے جواب کی ضرورت نہیں اسی طرح جن اعتراضات کے حق
میں کوئی ثبوت پیش نہیں کیا گیا ان کو دعوی بلا دلیل قرار دے کر چھوڑ دینا بھی عین درست ہوگا.لیکن اگر معترض کی
کتاب کے مقصد کو ظاہر کرنا اور اس مقصد کے حصول کی کوشش کو ناکام بنانا اس کاوش کا مقصد سمجھا جائے تو پھر ہر اُس
پہلو کو سامنے رکھنا ضروری ہوگا، جو ایک عام قاری کے دل میں شک پیدا کر سکتا ہے اور پھر اس شک کا عام فہم انداز
میں ازالہ کرنے کے لیے جس قدر بھی تفصیل بیان کرنی مناسب ہو، بیان کی جائے گی.پس اس کتاب میں یہ
طریقہ اپنایا گیا ہے تاکہ موجودہ دور میں لوگوں کے دلوں میں شبہات پیدا کرنے کی کوشش کو نا کام بنایا جائے اور اس
غرض کے حصول کے لیے تفصیل کے بیان سے پہلو تہی نہیں کی گئی.لیکن یہ خیال رکھنے کی بھی کوشش کی گئی ہے کہ
شک وشبہ کے ازالہ کی کوشش میں جواب
کو اتنا بھی پھیلا نہ دیا جائے کہ قاری کو بذات خود جواب
سمجھنے میں ہی مشکل ہو.ایک پہلو تکرار کا بھی ہے.کتاب میں اس بات کا خصوصی خیال رکھا گیا ہے کہ ہر اعتراض کے جواب میں
مضمون جامع ہو اور قاری کو ایک بات سمجھنے کے لیے بار بار گزشتہ صفحات کی طرف رجوع نہ کرنا پڑے.نیز ابن
Page 13
xiii
وراق جو قاری کو الجھانا چاہتا ہے، اس مذموم مقصد کو نا کام کرنے کے لیے اس کتاب میں قاری کی آسانی مدنظر
رکھی گئی ہے اور اس آسانی کے لیے بسا اوقات مضمون کو مختصر طور پر دہرایا بھی گیا ہے.پس یہ اعادہ اور تکرار مضمون
کی جامعیت اور اس کے تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے اور قاری کی آسانی کے لیے ضروری سمجھی گئی ہے.ایک اور بات اس ضمن میں درج کرنا مناسب معلوم ہوتی ہے کہ اعتراضات کے جواب دیتے ہوئے علما الزامی
طور پر معترضین کے مذہب اور ان کی کتب کی حقیقت بھی ظاہر کرتے اور بتاتے کہ پہلے اپنے گھر کی تو خبر لوا بعینہ
یہی اعتراضات تمہارے مذہب اور کتابوں پر بھی پیدا ہوتے ہیں.پس اے نادانو ! تعصب اور اسلام پر حملہ کے
شوق میں اپنے ہی بخیے ادھیڑ رہے ہو.نتیجہ یہ ہوتا کہ بجائے لینے کے دینے پڑ جاتے.اب ابن وراق سے
منسوب اس کتاب میں اعتراضات کرنے کے لیے ایک چالا کی یہ کی گئی ہے کہ نا معلوم مصنف خود کو Secular
اور Rationalist ظاہر کرتے ہوئے عیسائیت اور یہودیت کے خلاف ایسا طرز عمل اپنا تا ہے کہ جواب دیتے
وقت عیسائیت اور یہودیت کی قلعی نہ کھولی جائے.اعتراض کرتے ہوئے رویہ یہ اختیار کرتا ہے کہ وہ کسی بھی
مذہب کا پیروکار نہیں مگر حوالے زیادہ تر عیسائی مستشرقین کے ہی دیتا ہے.نیز تعصب بھی وہی جھلکتا ہے جو بالعموم
ایک تنگ نظر اور متعصب مذہبی ملا کی میراث ہے اور خاص طور پر عیسائی مستشرقین میں اسلام کے خلاف ملتا
ہے.اگر چہ یہ کوئی ایسی وجہ تو نہیں کہ اس بنیاد پر ہم یہ موقف اختیار نہ کرسکیں کہ اگر یہ اعتراض اسلام پر یا قر آن پر
اُٹھاؤ گے تو نتیجہ تمام مذاہب اور اُن کے صحائف سے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا لیکن پھر بھی کوشش زیادہ تر یہی کی گئی
ہے کہ جوابات میں تاریخی منطقی اور عقلی پہلو کو ہی مدنظر رکھا جائے اور ساتھ ساتھ قارئین کو یہ علم بھی ہوتا رہے کہ یہ
اعتراض صرف اسلام پر ہی نہیں بلکہ تمام ادیان عالم پر کیا جارہا ہے اور ابن وراق کو بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ خواہ کسی
بھی دجل سے کام لو، اسلام سے مقابلہ کرو گے تو نصیب میں نامرادی اور نکبت ہی لکھی جائے گی.چنانچہ زیر نظر کوشش میں اس پہلو کو مد نظر رکھا گیا ہے کہ اسلام ایسا کمزور اور مجبور نہیں ہے کہ اپنے خلاف
اُٹھائے جانے والے اعتراضات کے جواب کے سلسلہ میں دوسرے مذاہب کی کمزوریوں کے بیان کو بطور سہارا
استعمال کرے اور پھر ان مذاہب کا اپنی بنیادوں سے ہٹ جانا بھی علمی دنیا میں اب اتنا مسلم ہو چکا ہے کہ اس
کتاب میں زیادہ تفصیل سے ان کا بیان موجب طوالت اور تضیع اوقات ہوگا.چنانچہ برسبیل تذکرہ مختصر طور پر تو
اس حقیقت کو بیان کر دیا گیا ہے کہ ان اعتراضات کا شکار تمام مذاہب اور صحائف اس طرح ہوتے ہیں کہ کوئی
جواب بن نہیں پڑتا جبکہ اسلام ایک ایسا حصن حصین ہے کہ اس سے ٹکرا کر ہر اعتراض پاش پاش ہو جاتا ہے.اور
اسی محفوظ قلعہ کے اندر دوسرے مذاہب اور صحائف کو بھی پناہ لینا پڑتی ہے.اور دیانت دارانہ مطالعہ کے بعد یہی
نتیجہ نکلتا ہے کہ آخر کار مذاہب عالم کو اپنی سچائی کے ثبوت کے لیے اسلام سے بڑی اور کوئی دلیل نہیں مل سکتی.
Page 14
الذكر المحفوظ
xiv
فهرست عناوین
1
باب قرآن کریم کی لفظی محافظت تحریف قرآن کے ضمن میں لگائے
12
باتے
فصلا عہد نبوی میں جمع و تدوین قرآن جانے والے الزامات کے جوابات
1 شیطانی آیات 1 ابتداء نزول سے ہی کتابت قرآن کا اہتمام
103
105
قرآن کریم سے ثبوت
احادیث اور تاریخ سے ثبوت
iii جلد کاتبین وحی
iv معہد نبوی میں کتابت قرآن کا طریقہ اور ہی میں کتابت قرآن
V
ذرائع
15
17
21
24
2 واقعه ابی سرح
i لا خلاصه
رسول کریم ﷺ قرآن کریم میں کوئی
رد و بدل نہیں کر سکتے تھے
عہد نبوی میں قرآن کریم مکمل طور پر تحریری قرآن کریم سے ثبوت
صورت میں جمع ہو چکا تھا
2 حفظ قرآن کریم
الْفَضْلُ مَا شَهِدَتْ بِهِ الْأَعْدَاءُ
* تلاوت قرآن
4 تعلیم القرآن
24
27
37
38
49
iiحمد محمد مست بُرہان محمد
110
118
119
123
126
آنحضرت کی صداقت اور دیانت پر 126
گواہیاں
صلى الله
حضور ﷺ نے ہر
قسم کی آسائش کو رد کر دیا
اور قرآن میں کوئی رد و بدل قبول نہ کیا
136
آنحضرت ﷺ نے ہر قسم کی تکلیف کا 141
قرآن کریم حافظہ سے محو نہ ہونے دینا خدا مقابلہ کیا مگر قرآن میں رد و بدل قبول نہ کیا
تعالی کی ذمہ داری تھی
آنحضور ﷺ کی سعی مبارک
iii صحابہ کی گواہی
iv مخالفین کی گواہی
60
66
68
69
فتوحات کے بعد کی زندگی آنحضور کے 148
رد و بدل نہ کرنے پر دلیل ہے
vi آنحضور ﷺ کی صداقت کا ایک ثبوت 153
آپ کا ایمان کامل فصاح عہدِ خلافت راشدہ میں جمع قرآن vi آنحضور ﷺ کی صداقت کا ثبوت: صحابہ کا 162
ہ صحابہ کے دور میں جمع قرآن سے مراد اور اس کا محرک 81 غیر متزلزل ایمان
iiحمد عہد خلافت صدیقی میں جمع قرآن کا طریق 87 4 رسول کریم ﷺ کو قرآن کریم میں کسی
iii حمید صحابہ کے دور میں قرآن کریم میں رد و بدل
ناممکن تھا
98
iv قرآن مجید کے اعراب ( حرکات ) و نقاط 100
رڈ و بدل کا موقع نہیں تھا
174
Page 15
256
257
269
الذكر المحفوظ
5
ترتیب قرآن
ترتیب آیات
حلا ترتیب سور
XV
6177
177
178
آیت رجم
حضرت عائشہؓ سے مروی روایت
رسول کریم ﷺ اور خلفا راشدین کا رجم کی
iii سورتوں کی ترتیب پر قرآن کریم کی اندرونی 181 سزا تجویز کرنا
گواہی
V
iv چه ترتیب سور پر احادیث اور روایات سے دلائل 184
رسول کریم کی لگوائی ہوئی ترتیب بدلی نہیں گئی 186
7
8
اختلاف مصاحف
اختلاف قراءت
i فرق حرکات (اعراب) vi قرآن کریم کی احزاب یا منازل میں تقسیم 195
vii لا خلاصه
vii یہ حکم و عدل علیہ السلام کا ارشاد
x قرآن کریم کی ترتیب نزولی کے بدلنے میں
X
حکمت
* قرآن کریم کا حسن بیان
xi آخری طریق فیصلہ
204
204
ا فرق حروف
iii د اختلاف لغت
Riv ایک تحقیق
9 207
213
228
متفرق الزامات
قرآن کریم کے لفظ ”قل“ پر اعتراض
285
289
289
291
310
311
311
ii اعتراض محققین کے مطابق قرآن کریم کی 321
xii قرآن کریم کی معنوی ترتیب اور اس کا بہت سی آیات الحاقی ہیں
دستور بیان
236 iii حفاظت قرآن کے ضمن میں مستشرقین کی 345
xiii قرآن کریم کا اسلوب بیان بطریق درس و تعلیم 237 گواہیاں
xiv لا ترتیب مضامین قرآن
XV
238 i7 حفظ قرآن پر اعتراض
قرآن کریم ا کا اسلوب بیان عام طرز پر نہیں ہے 241 قرآن کریم کی معنوی محافظت
xvi قرآن کریم مضمون کو اس کی طبعی ترتیب سے
xvii
بیان فرماتا ہے
نظام ترتیب قرآن، قوانین قدرت کے
مطابق ہے
244
245
باب
مسئله ناسخ و منسوخ
352
365
383
قرآن کریم کی دائمی حفاظت کا وعدہ ہے 394
iii قرآن کریم کے بعد اور کسی الہامی کتاب
xvi * ترتیب قرآن عالم جسمانی اور عالم روحانی کے نزول کی ضرورت نہیں
کے مطابق ہے
246
248
انڈیکس
xix قرآن کریم کی ترتیب بیان باعتبار ظاہر
انڈیکس آیات قرآن کریم میں اعادہ و تکرار اور اس کا حقیقی فلسفہ 252
XX
xxi خلاصه
xx * قرآن کریم کی اجزاء اور رکوعوں میں تقسیم
254
255
ii انڈیکس اعتراضات
iii انڈیکس اسماء
398
399
Page 17
1
باب اول
قرآن کریم کی لفظی محافظت
اگر تمام دنیا میں تلاش کریں تو قرآن مجید کی طرح خالص اور محفوظ کلام الہی
کبھی نہیں مل سکتا.بالکل محفوظ اور دوسروں کی دستبرد سے پاک کلام تو صرف
قرآن مجید ہی ہے.(حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی معہود علیہ السلام)
تمہید
فصل عہد نبوی میں جمع و تدوین قرآن کریم
پندرہ (15) ذیلی عناوین
3
12
فصاح عبد خلافت راشدہ میں جمع و تدوین قرآن کریم 77
چار(4) ذیلی عناوین
Page 19
3
بسم اللہ الرحمن الرحیم
اللہ تعالیٰ سورۃ الحجر میں یہ مضمون بیان فرماتا ہے کہ قرآن کریم ایک ایسا نادر اور بے مثل کلام ہے کہ ایسے بہت
سے مواقع پیش آتے ہیں اور آتے رہیں گے کہ اس کی خوبیاں دیکھ کر کفار کے دل پر بھی رعب طاری ہو جاتا ہے.وہ بھی دل ہی دل میں کبھی حسرت کرتے ہیں کہ کاش ہم تسلیم کرنے والوں میں سے ہو جاتے.لیکن اس کے بعد
پھر اپنی پہلی حالت کی طرف لوٹ جاتے ہیں اور اپنے تکبر نخوت اور انانیت کی وجہ سے اس پر ایمان نہیں لاتے
اور اپنی بدبختی کی وجہ سے صداقت کو پہچاننے کے باوجود قبول کرنے سے محروم رہتے ہیں.پھر مخالفت برائے
مخالفت میں ایسے اندھے ہو جاتے ہیں کہ جانتے بوجھتے ہوئے تمسخر کرتے اور خدا سے ٹکر لے بیٹھتے ہیں.ایسے
لوگ سمجھتے نہیں جب ہم نے ایک کلام اتارا ہے تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنا مقصد حاصل کیے بغیر ہی مٹ جائے.وہ قائم رہے گا اور رکھا جائے گا اور اسے قبول نہ کرنے والے خود اپنا ہی نقصان کریں گے.فرمایا کہ اس کلام کی
مخاطب ساری دُنیا ہے پس اگر ساری دُنیا نے اسے نہ مانا اور ظلم و تعدی اور شرارت کی راہ سے مخالفت میں حد سے
بڑھ گئی تو ساری دُنیا تباہی کا شکار ہوگی.یہ سورت چار نبوی یا اس سے بھی پہلے نازل ہوئی جبکہ مسلمانوں کی ظاہری حالت بہت کمزور تھی.گنتی کے
مسلمان تھے اور وہ بھی زیادہ تر غر با.ایسے میں ٹکر لینے پر ساری دُنیا کو تباہ و برباد کر دیے جانے کے اندار اور تنبیہ
پر کفار حیرت کا اظہار کرتے اور مسلمانوں
کو تمسخر اور تضحیک کا نشانہ بناتے کہ تمہاری حالت تو ایسی ہے کہ ہم اس
چھوٹی سی بستی میں رہنے والے ہی جب چاہیں تمہیں مسل ڈالیں اور تم دُنیا پر فتح یاب ہونے کی بات کر رہے ہو.چنانچہ ایک طرف مسلمانوں سے استہزاء کرتے اور دوسری طرف بانی اسلام آنحضرت
صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے بارہ
میں کہتے کہ یہ تو ایک دیوانہ ہے (نعوذ باللہ ).قرآن کریم ان
کا یہ تمسخر ان الفاظ میں بیان کرتا ہے:
وَقَالُوْايَأَيُّهَا الَّذِى نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِكرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ (الحجر: 7)
اور انہوں نے کہا کہ اے وہ شخص جس پر یہ ذکرا تارا گیا ہے یقینا تو دیوانہ ہے
پہلے انبیاء سے بھی تمسخر ہوالیکن انبیاء سے تمسخر کرنے والے ہمیشہ نا کام ہوئے اور انبیاء ہمیشہ کامیاب ہوئے اسی
طرح اب بھی ہوگا.خدا تعالیٰ اپنے سلسلہ کو کامیاب کرے گا.لوگ یہ نہیں خیال کرتے کہ خدا تعالیٰ پر افترا کرنا ایسی
بات نہیں کہ اس سے صرف نظر کیا جائے.خدا خود اس امر کی حفاظت کرتا ہے کہ اس پر افترانہ کیا جائے اور بچے کلام کو
خاص امتیاز عطافرماتا ہے.اس کی قبولیت کے سامان پیدا کر دیتا ہے اور جو اسے قبول کرتے ہیں انہیں ادنیٰ حالت
سے اٹھا کر کمال تک پہنچا دیتا ہے.پس اب بھی یہی مقدر ہے اگر مخالف پروا نہیں کرتے تو نہ کریں.تو اس خزانہ کو
Page 20
الذكر المحفوظ
4
تقسیم کرتا چلا جا اور جو اسے قبول نہیں کرتے انہیں سمجھاتا چلا جا اور خدا سے دعائیں کر.یوں تو مخالفین پر حجت تمام کرنے کے لیے قرآن کریم نے اپنے الہی کلام ہونے کے بہت سے دلائل بیان
ا
کیے ہیں لیکن اس بیہودہ تمسخر کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے الہی کلام ہونے کی ایک ایسی دلیل بیان
فرمائی جو اس دور کے منکرین کے لیے چینج کی حیثیت رکھتی تھی.جو لوگ کہتے تھے کہ تمہارا تو یہ حال کہ ہم تمہیں اسی
بستی میں کچل دیں گے ان
کو للکارا کہ تم کچلنے کی بات کرتے ہو لیکن ہم تمہیں بتائے دیتے ہیں کہ اس کلام کی
حفاظت ہم خود کریں گے.چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:
إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحفِظُونَ - (الحجر: 10 )
یعنی یقیناً ہم ہی نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں.تم نے اسلام کو کیا کچلنا ہے، اسلام کے پیغام میں ادنیٰ سا تغیر و تبدل بھی نہیں کر سکو گے.تمہاری یہ خوش فہمی
تمہارے دیکھتے دیکھتے حسرت میں بدل جائے گی اور تم اپنی ان کوششوں میں اور حسرتوں میں ناکام و نامرادر ہو
گے اور اسی نامرادی میں مرو گے.تمہارے نقشِ قدم پر چلنے والی تمہاری نسلیں بھی انہی حسرتوں کو سینوں میں لیے
اس دُنیا سے کوچ کر جائیں گی پھر اُن کی نسلیں اور پھر اُن کی نسلیں اور نسلاً بعد نسل اسلام اور اسلام کے پیغام کو
نابود کرنے کی کوششیں کرنے والے اپنے نامراد انجام کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے قیامت تک انہی حسرتوں
کی آگ میں جلتے اور مرتے چلے جائیں گے مگر کسی دشمن کو سی زمانہ میں بھی اپنی مراد نہ آتی دیکھنا نصیب نہیں ہوگی.حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفتہ امسیح الثانی المصلح الموعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:
یہ ایک نہایت ہی زبردست آیت ہے اور ایسی عجیب ہے کہ اکیلی ہی قرآن مجید کی صداقت
کا بین ثبوت ہے.اس میں کتنی تاکیدیں کی گئی ہیں.پہلے ان لایا گیا ہے پھر نا کی تاکید نخن
سے کی گئی ہے اور پھر آگے چل کر ایک اور ان اور لام لایا گیا ہے.گویا تا کید پر تاکید کی گئی ہے.کفار نے إِنَّكَ لَمَجْنُون کے جملہ میں دوہری تاکید سے کام لے کر تمسخر کیا تھا.اس کے
جواب میں اللہ تعالی تاکید کے چار ذرائع استعمال کرتا ہے اور فرماتا ہے.إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ
وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ (الحجر: 10) سنو! ہم نے ہاں یقیناً ہم نے ہی اس شرف وعزت والے
کلام کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا ہے اور ہم اپنی ذات کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ یقیناً
ہم اس کی خود حفاظت کریں گے.اللہ اللہ کتنازور ہے اور کس قدر حتمی وعدہ ہے.( تفسیر کبیر جلد سوم زیر تفسیر المجر آیت 10 صفحہ 50)
اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ ایک اتفاق ہے کہ قرآن شریف آج تک محفوظ ہے؟ اسلامی تاریخ بتاتی ہے کہ یہ
Page 21
5
اتفاق نہیں بلکہ اس کی ظاہری حفاظت کے لیے خدا تعالیٰ نے دو بنیادی انتظامات فرمائے جن کا ذکر اس سورت کے
شروع ہی میں کیا گیا ہے.ابتدائے نزول ہی سے اس کی آیات لکھی جانے لگیں اور اس کی حفاظت کا سامان کیا
گیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہر زمانہ میں اسے ایسے عشاق عطا کیے جو اس کے ایک ایک لفظ کو حفظ کرتے اور رات دن
خود پڑھتے اور دوسروں کو سناتے ہیں.اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے کسی نہ کسی حصے کا نمازوں میں
پڑھنا فرض مقرر کر دیا اور شرط لگادی کہ کتاب میں سے دیکھ کر نہیں بلکہ حفظ کر کے پڑھا جائے.ایسے آدمیوں کا مہیا کرنا جو اسے حفظ کرتے اور نمازوں میں پڑھتے تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت
اور آپ کے اختیار سے
باہر تھا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ کہ ایسے
لوگ ہم پیدا کرتے رہیں گے جو اسے حفظ کریں گے.آج اس اعلان پر پندرہ سو سال ہو چکے ہیں اور قرآن مجید
کے کروڑوں حافظ گزر چکے ہیں اور آج بھی بے شمار حافظ ملتے ہیں جنہیں اچھی طرح سے قرآن کریم یاد ہے.ایک ذریعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کے لیے یہ مقرر فرمایا کہ ایسے سامان کر دیے کہ قرآن مجید
اپنے نزول کے معا بعد تمام دنیا میں پھیل گیا اور یوں اس میں تغیر و تبدل کا امکان ہی نہیں رہا.ایک ذریعہ قرآن مجید کی حفاظت کا یہ تھا کہ اسلامی علوم کی بنیاد قرآن مجید پر قائم ہوئی جس سے اس کی
ہر حرکت وسکون محفوظ ہو گئے.مثلاً نحو پیدا ہوئی تو قرآن مجید کی خدمت کے لئے.پھر مسلمانوں نے علم تاریخ
ایجاد کیا تو قرآن مجید کی خدمت کی غرض سے کیونکہ قرآن مجید میں مختلف اقوام کے بیان شدہ حالات آئے تھے
اُن کی تحقیق کے ساتھ ساتھ باقی دنیا کے حالات بھی جمع کر دیے.پھر علم حدیث شروع ہوا تو قرآن مجید کی
خدمت کے لیے تاکہ معلوم ہو سکے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے کیا معنے بیان فرمائے ہیں.پھر اہل فلسفہ کے قرآن مجید پر اعتراضات کے دفعیہ کے لیے مسلمانوں نے علوم فلسفہ کی تجدید کی اور علم منطق
کے لیے نئی اور زیادہ حق راہ نکالی.پھر مسلمانوں میں طب کی بنیاد بھی قرآن مجید کے توجہ دلانے پر ہی قائم ہوئی.اسی طرح نحو میں مثالیں دیتے تو قرآن مجید کی آیات کی اور ادب میں بھی بہترین مجموعہ قرآن مجید کی آیات کو
قرار دیا گیا.غرض ہر علم میں آیات قرآنی کو بطور حوالہ نقل کیا جاتا.مسلمانوں میں قرآن کریم کے خدمت کے لیے
دیگر علوم کی طرف رجوع کا ایک ضمنی فائدہ یہ بھی ہوا کہ پہلی کتابوں سے تو دنیوی علما کا طبقہ سخت بے زار تھا لیکن
مسلمانوں میں سے ان علوم کے ماہر ہمیشہ قرآن مجید کے خادم رہے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم سچے علوم
کا دشمن نہیں بلکہ مؤید ہے.مشہور مستشرق قلب کے حتی اس بارہ میں رقم طراز ہیں:
قرآن صرف ایک مذہب کا دل اور آسمانی بادشاہت کا رستہ دکھانے والا نہیں بلکہ وہ علوم و
Page 22
الذكر المحفوظ
6
فنون اور سائنس و حکمت کا نچوڑ اور ایسی تاریخی دستاویز ہے جس میں ارضی بادشاہت کے قوانین
بھی پیش کیے گئے ہیں.“
پھر لکھتے ہیں:
تاریخ عرب از فلپ کے حتی ، ناشر : آصف جاوید برائے نگارشات، باب 5 صفحہ 35 )
مسلمانوں کے نزدیک دینیات، فقہ اور سائنس دراصل ایک ہی شمع کی کرنیں ہیں.لہذا
تعلیم و تربیت کے لیے قرآن سائنس کے رہنما اور ایک درسی کتاب کی حیثیت اختیار کر جاتا
ہے.دُنیا کی سب سے بڑی اسلامی یونیورسٹی جامعہ الازہر جیسے ادارے میں اس کتاب کو اب
بھی سارے نصاب کی اساس قرار دیا جاتا ہے.“ (حوالہ مذکورہ صفحہ 37 )
قرآن کریم کی زبان نے دُنیا بھر کے مسلمانوں کو یکجا کیا اور انہیں ایک زبان قرآن کی زبان پر جمع کیا.ہر مسلمان جو قرآن کریم سیکھتا ہے اس زبان سے واقف ہوتا ہے.چنانچہ فلپ کے حتی لکھتے ہیں:
شام، عرب اور مصر کی طرح عراق اور مراکش میں ہر جگہ وہی کلاسیکل عربی زبان رائج ہے
جس کی تشکیل قرآن نے کی.“
(حوالہ مذکورہ صفحہ 37 )
دوسرے مذاہب کی کتب اپنے پیرو کاروں کو یکجا کیا کرتیں وہ تو خود اپنی زبانوں کو بھی زندہ نہ رکھ سکیں.مثلاً
وید کے بارہ میں اگر یہ فرض بھی کر لیا جائے کہ وہ لفظاً محفوظ ہیں تو بھی وہ کتاب کامل ہونے کے لحاظ سے محفوظ نہیں
کیونکہ جس زبان میں وہ نازل ہوئے وہ محفوظ نہیں رہی اس لیے اس کے معانی بالکل مشتبہ ہو کر رہ گئے ہیں.ان ظاہری سامانوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا ایک ایسا ذریعہ بھی مقرر کیا جو غیر اللہ کے
دخل سے بکلی پاک ہے اور وہ ہے الہام کا ذریعہ.یعنی قرآن کریم کی معنوی حفاظت کے لیے امت محمدیہ میں
مجد دین اور مامورین کی بعثت ہوتی رہے گی.چنانچہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کو بشارت
دیتے ہوئے فرمایا:
إِنَّ اللهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْس كُلَّ مِئَةَ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِيْنَهَا
(سنن ابی داؤد کتاب الملاحم باب ما جاء في قرن المائة)
یعنی اس امت کے لیے ہر صدی کے سر پر تجدید دین کے لیے اللہ تعالیٰ ضرور اپنے بندے مبعوث کرتا رہے گا.چنانچہ ایسا ہی ہوا اور ہر دور میں اللہ تعالیٰ کے الہام سے تائید یافتہ بندے قرآن کریم کی صحیح تعلیم سے دُنیا کو
فیضیاب کرتے رہے.چودہویں صدی کے سر پر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق
Page 23
7
حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی معہود علیہ السلام تشریف لائے.آپ نے فرمایا:
یا درکھو کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کیلئے غیور ہے.اس نے سچ فرمایا ہے إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا
لَهُ لَحفِظُون (الحجر: 10) اس نے اس وعدہ کے موافق اپنے ذکر کی محافظت فرمائی اور مجھے مبعوث کیا
اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدہ کے موافق کہ ہر صدی کے سر پر مجدد آتا ہے اس نے مجھے
صدی چہار دہم کا مجدد کیا جس کا نام کا سر الصلیب بھی رکھا ہے.ہم اس سے تائید میں پاتے
ہیں اور اس کی نصرتیں ہمارے ساتھ ہیں.( ملفوظات جلد دوم صفحہ 371-370)
اس تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ قرآنِ کریم کی پیروی سے وصالِ الہی کا مرتبہ پانے والے لوگ پیدا ہوتے
رہیں گے اور جب تک قرآن کریم کی پیروی کی برکت سے مجدد اور مامور اس امت میں پیدا ہوتے رہیں گے یہ
ثابت ہوتا رہے گا کہ قرآن کریم محفوظ ہے کیونکہ ذکر کے ایک معنے شرف اور نصیحت کے بھی ہیں.قرآن کریم
کا نام ذکر اس لیے رکھا گیا کہ اس کے ذریعہ سے اس کے ماننے والوں کو شرف اور تقویٰ حاصل ہوگا.پس انا
نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِكرَ وَإِنَّا لَهُ لَحفِظُونَ میں اللہ تعالیٰ اس امر کی طرف بھی اشارہ فرماتا ہے کہ یہ کلام جس سے
ماننے والوں کو شرف اور عزت اور تقویٰ ملے گا ہمارا ہی نازل کردہ ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں یعنی ان دعووں
اور وعدوں کو عملاً پورا کرنا ہمارا ہی کام ہے.اگر اس کی یہ صفات ظاہر نہ ہوں تو گویا اس کی تعلیم ضائع ہوگئی مگر ہم
ایسا نہیں ہونے دیں گے.آغاز وحی سے ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے زیر نگرانی قرآن کریم تحریری طور پر محفوظ کیا جانے لگا.یوں ابتدا سے ہی اس کا ایک مخصوص متن تھا جو ایک تو اتر کے ساتھ ہم تک پہنچا.ہر دور میں اس امر کی عقلی نفلی اور
اجتماعی گواہی موجود رہی ہے کہ جو متن قرآن کریم کا آج ہمارے پاس موجود ہے وہ بعینہ وہی ہے جو آپ نے دُنیا
کو دیا تھا.آپ پر جو بھی وحی نازل ہوتی آپ اسے اسی وقت لکھوا لیتے تھے.پھر ہر طرح تسلی کرنے کے بعد
چنیدہ صحابہ کو حفظ کر وادیتے جو حفظ کے سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہوئے دیگر صحابہ کو حفظ کراتے.علاوہ ازیں جب
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لکھوا کر صحابہ کو حفظ کرا دیتے تو پھر مختلف صحابہ اس نئی وحی کی نقول اپنے لیے بھی تیار
کر لیتے.یہ حفظ اور تحریرات گاہے گاہے آپ کی خدمت میں پیش کر کے مستند بنالی جاتیں.اس درجہ احتیاط اور
اخلاص کے ساتھ ساتھ بہت کثرت سے ہر تازہ وحی کو حفظ اور تحریری صورت میں محفوظ کیا جاتا کہ اس میں کسی قسم
کی تحریف کا راہ پا جانا ممکن نہیں رہتا تھا.پھر آپ وقتا فوقتا
صحابہ کے پاس محفوظ قرآن کریم کو چیک کرتے رہتے.اس کے ساتھ ساتھ تعلیم القرآن کا باقاعدہ ایک انتظام کے ساتھ سلسلہ جاری تھا جس کے نگرانِ اعلیٰ آپ صلی
Page 24
الذكر المحفوظ
8
اللہ علیہ والہ وسلم خود تھے.علاوہ ازیں صحابہ خود بھی عشق قرآن میں سرشار ہونے کی وجہ سے کثرت سے اس کی
تلاوت کرتے.گھروں میں، سفر و حضر میں، نمازوں میں، مجالس وغیرہ میں کثرت سے تلاوت ہوتی.غرض
اُترنے والی نئی وحی کی احتیاط کے سارے تقاضے پورے کرتے ہوئے اس طرح حفاظت، اشاعت اور پھر بار بار
دہرائی ہوتی کہ اس کا بدلنا یا بھولنا ناممکن ہو جاتا.صحابہ اس یقین کامل سے لبریز تھے کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم پر
نازل ہونے والا کلام ، کلام الہی ہے اور اس میں ان کے لیے نجات کا سامان ہے.چنانچہ وہ والہانہ محبت کے ساتھ
اس کی حفاظت اور تعلیم و تدریس میں منہمک رہتے اور نازل ہونے والی ہر آیت کو نزول کے ساتھ ساتھ فوراً حفظ
کرتے جاتے.صحابہ اپنا اپنا حفظ کیا ہوا قرآن کریم کا حصہ ایک دوسرے کو بھی سنایا کرتے اور اس بات کی کڑی
نگرانی رکھتے کہ کلام الہی میں ادنی اسی کمی بیشی بھی نہ ہو.اگر کبھی ادنی سا بھی شک ہوتا تو معاملہ فوراً رسول کریم صلی
اللہ علیہ والہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے اور آپ سے رہنمائی کی جاتی.جب رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی وفات ہوئی تو اس وقت خدا تعالیٰ کی طرف سے آپ پر نازل ہونے
والا یہ کلام آپ کی نگرانی میں تحریری طور پر صرف انصار مدینہ میں سے کم از کم پانچ صحابہ کے پاس پانچ نسخوں کی
صورت میں ایک معین متن کی شکل میں جمع کیا جاچکا تھا.پھر دیگر صحابہ کے تیار شدہ ذاتی نسخوں کے علاوہ آپ پر
نازل ہونے والی وحی کی بے شمار متفرق تحریرات موجود تھیں جو براہ راست آپ کے حضور پیش کر کے مستند بنائی گئی
تھیں جن پر آپ نے مہر تصدیق ثبت فرمائی تھی.پھر بلا مبالغہ ہزاروں ہزار حفاظ موجود تھے جنہوں نے آپ کی
وساطت سے اتری ہوئی خدائی راہنمائی کو اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا تھا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے
حضور تلاوت کر کے اس کی درستگی کی تصدیق کر والی تھی.یہ امر عام فہم ہے کہ کسی بھی شخص کے مزاج اور طبیعت کا اس کی شخصیت پر اثر ہوتا ہے.کسی کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا
پھرنا، معاشرت،سوچنے کا انداز ان سب کا ان نتیجوں سے تعلق ہوتا ہے جو وہ اپنے ماحول اور مختلف امور کے
مطالعہ سے اخذ کرتا ہے.مستشرقین اور محققین کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے.ہر مطالعہ کرنے والے پر یہ حقیقت بھی واضح ہے کہ ہر شخص کے طبعی رجحان اور ذہنی میلان کی سمت کا اس کے
اعمال پر بہت گہرا اثر ہوتا ہے.جن لوگوں کا مزاج نسبتاً سخت ہوتا ہے وہ بعض اوقات اصلاح معاشرہ کے لیے
نسبتا سخت رویہ اپنانے والے کو پسند کرتے ہیں جبکہ نرم دل لوگ وعظ و نصیحت کو زیادہ پسند کرتے ہیں.یہ ایک عام
فہم اور مسلّمہ حقیقت ہے چنانچہ زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں.طبائع کے اس اختلاف کی وجہ سے بعض
اوقات قطع نظر اس کے کہ متوازن اور بہترین طریق کیا ہے ایک طرز عمل ایک شخص کے دل کو بھاتا ہے اور کسی
دوسرے کے دل کو نہیں بھاتا اور اس کے نزدیک مزید بہتر صورت موجود ہوتی ہے.دوسری طرف یہ بھی حقیقت
Page 25
9
ہے کہ بعض دفعہ ایک محقق بعض حقائق کو بیان کرنے پر اس طرح مجبور ہو جاتا ہے کہ چاہتے ہوئے بھی اپنی سوچ
کے مطابق نتیجہ اخذ نہیں کر سکتا اور واضح طور پر اعتراف کرتا ہے کہ حقائق کا مجموعی مطالعہ ہمیں فلاں نتیجہ اخذ کرنے
پر مجبور کرتا ہے.اس کا انداز بتا رہا ہوتا ہے کہ وہ یہ نتیجہ اخذ کر کے یا اس حقیقت کا اعتراف کر کے دلی طور پر خوش تو
نہیں
لیکن اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا.مغربی محققین اور مستشرقین کے ہاں اسلام کے بارہ میں تحقیق میں بالعموم تعصب اور اسلام دشمنی کا عنصر بہت
حد تک
کارفرما دکھائی دیتا ہے.ایک خاص طرز فکر ، بنیادی اسلامی مآخذ سے نا آشنائی ، عربی سے عدم واقفیت اور
مخالفانہ اور متعصب اُٹھان کی وجہ سے مستشرقین کی تحقیقات میں بار ہا یہ نظر آتا ہے کہ واضح حقائق کو عمداً نظر انداز
کیا جارہا ہے اور بلاوجہ تنقید کی جارہی ہے جو اکثر اوقات تحقیق کے اپنے مسلمہ اصولوں کے بھی خلاف ہوتی ہے لیکن
اس رویہ کے باوجود تحقیق کے کچھ میدان ایسے ہیں جہاں بسا اوقات تمام تر حقائق پر نظر ڈالنے کے بعد وہ بھی مجبور
ہو جاتے ہیں کہ اپنی مرضی کے خلاف اور درست نتیجہ نکالیں.گو ایسے موقعوں پر الفاظ میں تعصب تو وہی جھلک رہا
ہوتا ہے جو دل میں ہوتا ہے لیکن کوئی بس نہیں چلتا.چنانچہ محافظت قرآن شریف کے میدان میں کچھ ایسا ہی نظارہ
نظر آتا ہے.قرآن کریم کے محفوظ ہونے کے بارہ میں حقائق ایسے روشن اور واضح ہیں کہ جن کا مطالعہ کرنے والا
ہر دیانت دار محقق با وجود نظریاتی اختلاف اور مخالفت کے اس بات کا کھلم کھلا اظہار کرتا ہے کہ قرآن کریم بلاشبہ
محفوظ ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی.پیش لفظ میں ویلیم میور اور نولڈ یکے کی مثال گزر چکی ہے.لیکن دشمنی اور تعصب میں حد سے گزرنے والے کچھ سر پھرے ایسے بھی ہیں جن کی عقلیں اس درجہ موٹی ہیں
کہ وہ سمجھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے روشن کیے ہوئے اس چراغ کو اپنے مونہوں کی پھونکوں سے بجھانے میں کامیاب
ہو جائیں گے.وہ سمجھتے ہیں کہ گزشتہ زمانوں میں ان کے عمائدین کو شائد پورا پورا موقع نہیں ملا اس لیے نامرادی
کے داغ چہروں پر سجائے گزر گئے.ہم آج پھر زور لگائیں تو کامیاب ہو جائیں گے.ان میں سے ایک محقق ابن وراق
نے اس بات کو پس پشت ڈال کر کہ خدا تعالیٰ قرآن کریم کی حفاظت کا خود ضامن ہے اور اس حقیقت کی صداقت کا
ثبوت پندرہ صدیوں پر محیط عرصہ ہے، حفاظت قرآن پر ایک مرتبہ پھر حملہ کرنے کی جرات کی ہے.لکھتا ہے:
We need to retrace the history of the Koran text to
understand the problem of variant versions and variant
readings, whose very existence makes nonsence of the
muslim dogma about the Koran.As we shall see, there is
no such thing as the Koran; there never has been a
definitive text of this holy book.When a Muslim
dogmatically asserts that the Koran is the word of God,
we need only ask "Which Koran?" to undetermine his
certainty.
Page 26
10
الذكر المحفوظ
After Muhammad's death in A.D.632, there was no
collection of his revelations.Consequently, many of his
followers tried to gather all the known revelations and
write them down in codex form.Soon we had the
codieced of several scholars such as Ibn Mas`ud, Ubai b.Kab, Ali, Abu Bakr, al-Ash`ari, al Aswad, and others.As
Islam spread, we eventually had what became known as
the Metropolitan Codices in the centers of Mecca,
Medina, Damascus, Kufa and Basra.As we saw earlier,
Uthman tried to bring order to this chaotic situation by
canonising with Medinan Codex, copies of which were
sent to all the metropolitan centers with order to destroy
all the other codices.(Ibn Warraq: Why I am Not A Muslim, Prometheus Books, New
York, 1995, under heading; The Koran: Pg 108-109)
ہمیں مختلف versions اور مختلف قراءتوں کے مسائل کو سمجھنے کے لیے قرآنی متن کی
تاریخ کو دوبارہ کھنگالنے کی ضرورت ہے جن کا وجود ہی قرآن کریم کے بارہ میں مسلمانوں کے
عقیدہ کا بودا پن ثابت کرنے کے لیے کافی ہے.جیسا کہ ہم دیکھیں گے کہ قرآن نام کی کسی چیز
کا کوئی وجود ہی نہیں.اس مقدس کتاب کا کوئی خاص متن کبھی بھی سامنے نہیں آیا.جب ایک
مسلمان اپنے اس عقیدہ کا اظہار کرتا ہے کہ قرآن خدا کا کلام ہے تو ہمیں اس کا یقین متزلزل
کرنے کے لیے صرف یہی پوچھنا کافی ہوتا ہے کہ کون سا قرآن؟“
(حضرت) محمد (ﷺ) کی وفات 632ء کے بعد آپ پر نازل ہونے والی وحی کا کوئی
مجموعہ موجود نہیں تھا.دریں اثناء آپ کے بہت سے صحابہ نے تمام معلوم وحی کو جمع کرنے کی کوشش
شروع کر دی اور اسے متن کی صورت میں لکھ لیا.چنانچہ جلد ہی بہت سے علما، جیسے ابن مسعود،
أبي بن کعب، علی، ابوبکر ، الاشعری، الاسود اور دوسرے صحابہ (رضوان اللہ علیہم اجمعین ) کے
مجموعے دستیاب تھے.اسلام کے پھیلتے ہی ہمارے پاس آخر کار چند مرکزی صحائف اکٹھے ہو گئے
جو مکہ، مدینہ دمشق، کوفہ اور بصرہ میں تھے.جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ عثمان نے صحیفہ کی اس نا گفتہ بہ
حالت کی مدنی صحیفہ کے مطابق تدوین کے ذریعہ اصلاح کی کوشش کی جس کی نقول اس حکم کے ساتھ
دوسرے نئے اسلامی مراکز میں بھجوادی گئیں کہ دیگر تمام نسخہ ہائے قرآن تلف کر دیے جائیں.اس چھوٹے سے بیان میں ابن وراق جتنا جھوٹ بھر سکتا تھا اس نے بھر دیا ہے.خصوصاً پہلے پیرے میں کیے
ہوئے جھوٹے دعوے کو سچا ثابت کرنے کے لیے دوسرے پیرے میں مزید تلبیس ، جھوٹ اور فریب سے کام لیا
ہے.حالانکہ یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ قرآن کریم کا کبھی بھی کوئی مخصوص اور معتین متن نہیں رہا اور آپ کی وفات کے
Page 27
11
بعد لوگوں نے جو حصہ ہائے وحی ملے انہیں لکھ لیا.اس اعتراض کے جواب کے لیے ہم ابن وراق کی خواہش کے
مطابق تاریخی حقائق کی روشنی میں قرآن کریم کی جمع و تدوین کے مراحل پر نظر ڈالتے ہیں.قرآن کریم کی جمع و تدوین کا زمانہ در اصل حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم اور خلافت راشدہ کے دور
تک ممتد ہے.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نگرانی میں قرآن کریم کو ہر طرح محفوظ کر چکے تھے اور اس کا متن
اور اس کی تعلیمات آپ کے حین حیات ہی شائع ہو چکی تھیں.آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ
نے قرآن کریم کی جو گراں قدر خدمات سرانجام دیں اُن میں قرآن کریم کی تحریر کو کمال احتیاط اور دیانت داری
کے ساتھ ایک جلد میں ایک مستند مرکزی نسخہ کی شکل میں پیش کرنا، اختلاف قراءت کا حل اور کثرتِ اشاعت
شامل ہے.ذیل کی سطور میں ہم الگ الگ فصول میں ان دونوں ادوار کا تاریخی مطالعہ کریں گے کہ کس طرح خدا
تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت اور اس کی جمع کے وعدہ کو معجزانہ رنگ میں پورا فرمایا.اس بحث کے تاریخی پہلو کو بنیادی طور پر ہم دوحصوں میں تقسیم کرتے ہیں.1.حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی حیات مبارکہ میں قرآن کریم کی جمع و تدوین اور
2 - خلافت راشدہ کے دور مبارک میں قرآن کریم کی جمع و تدوین
Page 28
الذكر المحفوظ
12
عہد نبوی میں جمع و تدوین قرآن
قرآن کریم حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم پر ساڑھے بائیس سال سے زائد عرصہ میں نازل ہوا.نزول کی یہ انتہائی معمولی رفتار قرآن کریم کی ایک ایسی خصوصیت ہے جس کے بے شمار فوائد اور حکمتیں پوشیدہ
ہیں.ان میں سے ایک فائدہ حفاظت کے ذرائع کے حوالہ سے بھی ہے.قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:
و قُرْآنًا فَرَقْنهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاس عَلى مُكْثٍ وَ نَزَّلْنَهُ تَنْزِيلًا (بنی اسرائیل : 107)
ترجمہ: اور قرآن وہ ہے کہ ہم نے اسے ٹکڑوں میں تقسیم کیا ہے تاکہ تو اسے لوگوں کے
سامنے ٹھہر ٹھہر کر پڑھے اور ہم نے اسے بڑی قوت اور تدریج کے ساتھ اتارا ہے
علامہ زرکشی لکھتے ہیں کہ قرآن مجید کا زمانہ نزول بائیس سال پانچ ماہ اور چودہ دن ہے.( بدرالدین محمد بن عبد الله الزرکشی : البرهان فی علوم القرآن.الجزء الاول صفحہ 314
ناشر دار احياء الكتب العربية ،مصر)
حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ عنہ اپنی ایک تحقیق یہ بیان فرماتے ہیں کہ نزول کی اوسط رفتار، فی آیت
روزانہ بھی نہیں بنتی کیونکہ ایام نبوت تقریباً 7970 بنتے ہیں.جبکہ آیات قرآنی 6236، الفاظ کی تعداد 77934
ہے.اس لحاظ سے فی آیت اوسطاً 12 الفاظ بنتے ہیں جبکہ نزول روزانہ اوسطاً 9 الفاظ کا ہوا.ہر آیت یا کسی بھی
قرآنی حصہ کے نزول کے ساتھ ہی آنحضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم فوری طور پر مقررشدہ لوگوں میں سے کسی کا تب کو
بُلا کر اس نئی نازل ہونے والی وحی کو اپنی نگرانی میں تحریری شکل میں بھی محفوظ کروا لیتے اور صحابہ کو حفظ بھی
کروا دیتے.آنحضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا حافظہ اور عربوں کا حافظہ ذہن میں رکھ کر جب غور کریں کہ اس شان
کے حافظہ کے ساتھ اتنی کم رفتار سے نازل ہونے والا قرآن جو نزول کے وقت ہی تحریر کے ساتھ ساتھ حفظ کی
صورت میں سینوں میں بھی محفوظ ہوتا جار ہا تھا اور دن رات اس کی درس و تدریس کا ایک سلسلہ جاری رہتا جس کی
نگرانی آپ کرتے تھے ، تو معلوم ہوتا ہے کہ ناممکن ہے کہ کوئی لفظ بھی محفوظ ہونے سے رہ جا تا.نزول کی اوسط
رفتار نکالنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اندازہ ہو سکے کہ قرآن کریم کے نزول کی رفتار عام طور پر اتنی کم تھی کہ اس کی
حفاظت اور اشاعت کرنے کے حوالہ سے کسی قسم کی مشکل پیش نہیں آتی تھی.بلکہ انتہائی آسانی سے یہ تمام مراحل
طے پاجاتے تھے اور ہنگامی بنیادوں یا جلد بازی سے کاموں میں جو سقم رہ جایا کرتے ہیں، یہ کتاب ان سے بکتی
پاک تھی.یہ انداز نزول اپنے اندر بہت سی حکمتیں سموئے ہوئے ہے جن کا محافظت قرآن سے براہِ راست تعلق
Page 29
عہد نبوی میں جمع و تدوین قرآن
ہے.اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے:
13
وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةٌ وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ
فُؤَادَكَ وَ رَتَّلْنَهُ تَرْتِيلاً - (الفرقان: 33 )
ترجمہ: اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ کہیں گے کہ اس پر قرآن یک دفعہ کیوں نہ اُتارا گیا.اسی طرح ( اُتارا جانا تھا) تا کہ ہم اس کے ذریعہ تیرے دل کو ثبات عطا کریں اور (اسی طرح)
ہم نے اسے بہت مستحکم اور سلیس بنایا ہے.اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن کریم کے آہستہ آہستہ نزول کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور
مومنین کے دلوں میں راسخ کرنے اور اس کو حرز جان بنانے میں بنیادی کردار ہے.چنانچہ یہ کئی طرح سے ہوا :
اول: اگر ایک ہی دفعہ سارا قرآن کریم نازل ہو جاتا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے استدلال کرتے
رہتے تو آپ کے دل کو ایسی تقویت حاصل نہیں ہو سکتی تھی جیسے کسی امر کے متعلق فوراً کلام الہی کے نزول سے
ہوسکتی ہے.وہ لطف اور اثبات آپ کو اجتہاد اور استدلال سے نہیں ملنا تھا جو عین ضرورت کے وقت خدا کے
ہم کلام ہونے سے ملتا تھا.دوم: جو کتاب ساری دُنیا کے لیے آئی اس کا محفوظ رکھنا اس طرح آسان ہوگیا کہ اسے نزول کے ساتھ ساتھ ہی تحریری
طور پر اور حفظ کے ذریعے محفوظ کیا جاتا.اگر اکٹھا نازل ہوتا تو پھر وہی حفظ کر سکتا جو اپنی ساری زندگی اس کام کے لیے
وقف کر دیتا.مگر اس طرح نزول
کا فائدہ یہ ہوا کہ سینکڑوں لوگ ساتھ ساتھ اس کے حفظ کرنے کے لیے تیار ہو گئے.سوم : قلوب میں اسلامی تعلیم راسخ ہونے میں اس طرز نزول کا اہم کردار تھا.اگر اکٹھا نازل ہو جاتا تو اس وقت
لوگوں پر اس کی تعلیمات کا سیکھنا اور ان پر عمل کرنا گراں ہو سکتا تھا.مگر آج اس کی ضرورت نہیں کیوں کہ اب اگر کوئی
مسلمان ہوتا ہے تو اس کے سامنے بہت سے مسلمانوں کا طرز عمل ہوتا ہے اور اسے ان تعلیمات پر عمل کرنے میں
دشواری پیش نہیں آتی.چهارم: رَتَّلْنَهُ تَرْتِيلاً کے الفاظ میں یہ بیان کر دیا کہ اس کی ترتیب بھی دو طرح سے ہوئی تھی.ایک ابتدائی
حالات کے مطابق اور ایک دائمی ترتیب جو نزول کے ساتھ ساتھ قائم کی جارہی تھی.اگر ایک ہی دفعہ قرآن کریم
نازل ہوتا تو اس کی ترتیب یہی ہوتی جو آج ہے.مگر یہ ترتیب اُس دور کے لیے مفید نہ تھی جیسا کہ اُس دور کی
ترتیب آج کے لیے غیر مفید ہے.پنجم : ایک ہی دفعہ قرآن کریم نازل ہونے میں کئی امور جو ابتدائی زمانہ میں صحابہ کے ازدیاد ایمان کا
موجب ہوئے ، بیان نہ ہو سکتے تھے.مثلاً قرآن کریم کی ایک آیت دوسری آیت کی طرف اشارہ نہ کر سکتی.مثلاً
Page 30
الذكر المحفوظ
14
قرآن کریم میں یہ پیشگوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں کے نرغہ کے نکال کر صحیح سلامت
لے جائے گا.اگر ایک دفعہ سارا قرآن نازل ہوتا تو یہ نہ کہا جاسکتا تھا کہ دیکھو ایسا ہی ہوا.یہ اسی صورت میں ممکن تھا
جبکہ پیشگوئی والا حصہ پہلے نازل ہو چکا ہوتا اور اس کی طرف اشارہ کرنے والا حصہ بعد میں نازل ہوتا.حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی معہود علیہ السلام فرماتے ہیں:
کافر کہتے کہ کیوں قرآن ایک مرتبہ ہی نازل نہ ہوا.ایسا ہی چاہیے تھا تا وقتا فوقتا ہم تیرے
دل کو تسلی دیتے رہیں اور تا وہ معارف اور علوم جو وقت سے وابستہ ہیں اپنے وقت پر ہی ظاہر
ہوں کیونکہ قبل از وقت کسی بات کا سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے سو اس مصلحت سے خدا نے قرآن شریف
کو تئیس برس تک نازل کیا تا اس مدت تک موعود نشان بھی ظاہر ہو جائیں.(حقیقۃ الوحی روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 357)
ششم : اگر ایک ہی بار یہ کتاب دے دی جاتی تو کوئی کہ سکتا تھا کہ کسی نے یہ کتاب بنا کر دے دی ہے.مگر
اس طرح کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کیونکہ اگر مکہ میں کوئی بنا کر دیتا تھا تو مدینہ میں کون دیتا تھا؟ پھر سفر و حضر میں قرآنی
آیات نازل ہوئیں مجالس میں نازل ہوئیں اور علیحدگی میں بھی نازل ہوئیں.دن کے اوقات میں بھی نازل
ہوئیں اور رات کی تاریکیوں میں بھی نازل ہوئیں.اس طرح یہ شک نابود ہو گیا کہ کوئی شخص یہ کلام بنا کر دے رہا
ہے.جب ہر موقع اور محل کے مطابق آیات نازل ہور ہیں تھیں تو کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ ہر موقعہ پر کوئی آپ کو
کلام بنا کر دے دیتا ہے.ہفتم: قرآن کریم کا یہ انداز نزول کتب سابقہ میں درج پیشگوئیوں کے عین مطابق ہے.ایک طرف عربوں کا مشہور زمانہ حیرت انگیز حافظہ اور دوسری جانب نزول کی رفتار اتنی کم.اس حقیقت کو
مد نظر رکھتے ہوئے اب ہم قرآن کی حفاظت کے ان ظاہری ذرائع کو دیکھتے ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نے خدا تعالیٰ کی راہنمائی کے مطابق اختیار کیے.مثلا کتابت قرآن، حفظ قرآن، تلاوت قرآن تعلیم القرآن،
وغیرہ.ذیل میں ان ذرائع کی کچھ تفصیل بیان کی جاتی ہے تا کہ قاری کو اندازہ ہو سکے کہ کس درجہ جانفشانی اور
عشق و محبت اور اخلاص و وفا کے ساتھ قرآن کریم کی حفاظت کا انتظام کیا گیا اور جن لوگوں نے یہ انتظام کیا،
انہوں نے قرآن کریم میں رد و بدل نہ کرنے کی ہر قیمت چکائی.ابتداء نزول سے ہی کتابت وحی قرآن کا اہتمام
ابن وراق کو یہ خبر جانے کہاں سے پہنچی ہے کہ قرآن کریم کا کبھی کوئی مخصوص متن نہیں رہا.اس بات کے قطعی
ثبوت ملتے ہیں کہ تحریری طور پر جمع قرآن کا کام ابتداء سے ہی شروع ہو گیا تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم
Page 31
عہد نبوی میں جمع و تدوین قرآن
15
نے ابتدائی ایامِ نبوت سے ہی وہی قرآن تحریر کروانا شروع کر دی تھی.اس حقیقت کو متقین تسلیم کرتے ہیں.ایام قرآن کر دی اس حقیت تقی کر
مشہور مستشرق اور رومن کیتھولک من کیرم آرمسٹرانگ لکھتی ہیں:
جب بھی کوئی آیت پیغمبر اسلام پر نازل ہوتی ، آپ اسے بلند آواز میں صحابہ کرام کو سناتے
جو اسے یاد کر لیتے اور جو لکھنا جانتے تھے ، اسے لکھ لیتے.( محمد : باب دوم ، صفحہ 61 پبلشرز علی پلاز 30 مزنگ روڈ لا ہور )
اس سلسلہ میں بہت سے دلائل ملتے ہیں جنہیں مختلف انواع میں تقسیم کیا جاسکتا ہے.ذیل میں چند ایک
دلائل درج کیے جاتے ہیں.قرآن کریم سے ثبوت
ایک بہت بڑی گواہی اس بات کی کہ نزول کے ساتھ ساتھ قرآن کریم تحریر کیا جارہا تھا، قرآن کریم سے یہ ملتی
ہے کہ قرآن کریم کی پہلی وحی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:
اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (العلق : 2)
یعنی اپنے رب کے نام سے پڑھ جس نے پیدا کیا ہے
یہ پہلی وحی ہے اس لیے ظاہر ہے کہ جب یہ نازل ہوئی اس وقت وہی قرآن کی کوئی تحریری صورت نہ تھی اس
لیے اِقْرَأْ الْكِتَابَ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِی خَلَقَ نہیں کہا گیا.مگر اس کے بعد باقاعدہ کتاب کے لفظ کا استعمال
قرآن کریم نے شروع کر دیا.گویا پہلی وحی کے بعد اسے تحریری شکل میں محفوظ کرتے ہی قرآن کریم کا ایک تحریری وجود
تشکیل پانے لگا جس پر لفظ کتاب کا اطلاق ہوتا تھا.اگر ایسانہ ہوتا تو ضرور مخالفین رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم
پر یہ اعتراض کرتے کہ کتاب کا ذکر تو کرتے ہیں مگر کتاب نظر نہیں آتی.چنانچہ بار بار یہ لفظ قرآن کریم میں
استعمال ہوا ہے اور ابتدائی دور میں کسی دوست یا دشمن نے یہ اعتراض نہیں کیا کہ یہ غلط بیانی کی جارہی ہے.قرآن کریم تو تحریری شکل میں موجود ہے ہی نہیں پھر کیوں کر اسے کتاب کہا جارہا ہے؟ سورۃ الفرقان میں کفار کا
قول محفوظ کیا گیا ہے کہ اُن
کو علم تھا کہ قرآن کریم کی تحریر کا کام زور وشور سے جاری ہے.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:
وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا (الفرقان :6)
اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو گزشتہ لوگوں کے قصے ہیں جو اس نے لکھوا لیے ہیں اور دن رات اس
کے سامنے ان کی املا کروائی جاتی ہے.سورة الفرقان سورۃ مریم سے قبل نازل ہوئی تھی.(البرھان فی علوم القرآن جزء اول صفحہ 193 ) اور
سورۃ مریم چار نبوی کے آخر میں نازل ہونے والی سورت ہے جو پہلی ہجرت حبشہ سے قبل نازل ہو چکی تھی کیونکہ
Page 32
الذكر المحفوظ
16
در بار نجاشی میں اس کے ابتدائی حصہ کی تلاوت کی گئی تھی.(السیرة النبويه لا بن هشام جزء اول صفحه 360) اس
لحاظ سے سورۃ الفرقان کا زمانہ نزول نبوت کا دوسرا یا تیسرا سال بنتا ہے.مشہور متعصب مستشرق ریونڈ وھیری بھی
یہ اعتراف کرتا ہے کہ یہ سورت بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوئی.The most that can be said of the date of revelation of
this chapter is that they belong to an early period in
Muhammad's ministry of Makkah.(A comprehensive commentry of the Quran by Rev.E.M.Wherry
vol.3 Page 207)
یعنی اس سورت کے متن کی وحی کے بارہ میں زیادہ سے زیادہ یہی کہا جاسکتا ہے کہ یہ حمد (ﷺ) کی
دعوت کے ابتدائی مکی دور کی ہے.پس بالکل ابتدائی زمانہ نبوت میں نازل ہونے والی سورۃ الفرقان میں کفار ہی کا قول محفوظ کیا گیا ہے جس
کے مطابق قرآن نہ صرف یہ کہ لکھا جاتا تھا بلکہ اس کثرت سے لکھا جاتا کہ گویا رات دن اس کی املاء کروائی جارہی
تھی.پس ابتدائی زمانہ نبوت سے ہی قرآن
کریم کی تحریر کا کام اس انداز میں ہور ہا تھا کہ مخالفین کو بھی علم تھا.ذیل
میں چند مزید مثالیں درج کی جاتی ہیں:
هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ آيَتِهِ وَيُزَكِّيْهِمْ
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَبَ وَالْحِكْمَةَ - (الجمعة:3)
یعنی وہی ہے جس نے امی لوگوں میں انہی میں سے رسول بھیجا جو ان پر آیات کی تلاوت
کرتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور الکتاب کی تعلیم دیتا ہے اور اس کی حکمت سکھاتا ہے.اللهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَبًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِي (الزمر: 24)
اللہ تعالیٰ نے سب سے خوبصورت بیان ایک دوسرے سے ملتے جلتے مضامین بیان کرنے
والی کتاب کی صورت میں اُتارا ہے
إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِكرِ لَمَّا جَاءَ هُمْ وَإِنَّهُ لَكِتُبٌ عَزِيزٌ لَّا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ
مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ (حم
السجدة: 43،42)
ترجمہ: یقینا وہ لوگ ( سزا پائیں گے ) جنہوں نے ذکر کا، جب وہ اُن کے پاس آیا، انکار
کر دیا حالانکہ وہ ایک بڑی غالب اور مکرم کتاب کی صورت میں تھا.جھوٹ اُس تک نہ سامنے
سے پہنچ سکتا ہے اور نہ اس کے پیچھے سے.بہت صاحب حکمت ، بہت صاحب تعریف کی طرف
Page 33
عہد نبوی میں جمع و تدوین قرآن
سے اس کا اتارا جانا ہے.17
اور بھی بہت سی آیات ایسی ملتی ہیں جن میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ قرآن کریم تحریری صورت میں موجود تھا.سارے زمانہ نزول میں قرآن کریم اپنے لیے لفظ ”کتاب“ استعمال کرتا چلا جاتا ہے جو دراصل ایک دعوی ہے
کہ قرآن کریم ابتداء نزول سے لکھا جاتا رہا ہے اور مخالفین کی نہ صرف اس دعوئی پر خاموشی بلکہ مختلف مقامات پر
اس حقیقت کا واضح الفاظ میں اعتراف کرنا اس دعوی کی صداقت پر علاوہ دوسرے دلائل کے ایک بڑی دلیل
ہے.علاوہ ازیں بہت سی مستند تاریخی شہادتیں بھی اس حقیقت کی مؤید ہیں.احادیث اور تاریخ سے ثبوت
ام خالد بنت خالد بن سعید بن العاص کی روایت ہے کہ بسم الله الرحمن الرحیم سب سے پہلے
میرے والد ( خالد بن سعید ) نے لکھی تھی اور خالد بن سعید باختلاف روایات تیسرے یا چوتھے یاپانچویں نمبر پر ایمان
لانے والے ہیں.آپ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد ایمان لائے اور السَّابِقُونَ الْأَوَّلُون میں سے تھے.(الاصابة في تمييز الصحابه الجزء الاول صفحه
(406
اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان سے قبل بعض مقتدر صحابہ مثلاً حضرت علی و حضرت عثمان و حضرت ابوبکر
وغیرہ (رضوان
اللہ علیہم اجمعین ) ایمان لا چکے تھے.نیز اس بات کا واضح اشارہ ملتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم
کے علاوہ وحی حضرت خالد بن سعید کے ایمان لانے سے قبل لکھی جارہی تھی اور اگر بسم اللہ کا نزول پہلی مرتبہ ان
کے ایمان لانے سے متصل نہیں ہوا تھا تو بسم اللہ بھی لکھی جاچکی ہوگی.خصوصاً اس صورت حال میں کہ جب
ایمان لانے والے اپنے آپ
کو مخفی رکھتے تھے اور کئی مومن ایک دوسرے سے واقف بھی نہیں تھے.اس لیے
روایات میں اس بارہ میں اختلاف ہے کہ کون کس نمبر پر ایمان لایا.حضرت خالد بن سعید کے ہاتھ کے لکھے
ہوئے نسخہ قرآن کا ذکر کتاب المصاحف میں ملتا ہے کہ یہ نسخہ حرف بحرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا تھا.(كتاب المصاحف لابن ابى داؤد الجزء الثالث: ص 104 اختلاف خطوط المصاحف)
حضرت ابوبکر ، حضرت عثمان، اور حضرت علی رضوان اللہ علیہم اجمعین بالکل ابتداء میں ایمان قبول کرنے
والوں میں سے ہیں اور یہ سب لکھنا پڑھنا جانتے تھے اور کاتبین وحی میں بھی شامل تھے یعنی آنحضور نے ان صحابہ
کی کتابت وحی پر با قاعدہ ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی.اس لیے غالب امکان ہے کہ پہلا کا تب وحی بھی انہی میں سے
کوئی ہوگا.چنانچہ تاریخ میں ذکر ملتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے وقت جب بدبخت قاتل نے
آپ پر تلوار کا وار کیا تو اپنے بچاؤ کے لیے آپ نے اپنا دایاں ہاتھ آگے کر دیا.وار ہاتھ پر پڑا اور آپ کی انگلیاں
کٹ گئیں.اس پر آپ نے فرمایا کہ یہ وہ ہاتھ تھا جس نے سب سے پہلے قرآن مجید تحریر کیا تھا.
Page 34
الذكر المحفوظ
18
کتابت وحی کا ایک زبر دست تاریخی ثبوت جو تاریخ اسلام کا ایک اہم ورق بھی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ
کے قبول اسلام کا ایمان افروز واقعہ ہے.جب آپ آنحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم کو ( نعوذ باللہ ) قتل کرنے
کے ارادہ سے گھر سے نکلے اور راستہ میں معلوم ہوا کہ خود اپنی بہن اور بہنوئی ایمان لا چکے ہیں تو غصہ میں ان کے
گھر کی طرف چلے گئے.وہاں آپ کے بہنوئی حضرت خباب بن الارت قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے.آہٹ پاکر حضرت عمر کی بہن فاطمہ نے خباب رضی اللہ عنہ کو اور ان اوراق کو جن پر قرآن لکھا ہوا تھا چھپا دیا.پھر
بعد میں حضرت عمر نے ان سے وہ اور اق لے کر پڑھے.یہ واقعہ سنہ 5 یا 6 نبوی کا ہے.(شرح القسطلانی الجزء الاول
صفحہ 272) اور اس بات کا بہت بڑا ثبوت ہے کہ قرآن کریم ابتدائی زمانہ سے جبکہ اسلام اپنی کمزور حالت میں تھا
لکھا جاتا تھا.اس مشہور روایت میں واضح طور پر اس بات کا ذکر ہے کہ اس ابتدائی زمانہ میں صحابہ کے پاس تحریری
شکل میں قرآن کریم موجود تھا.پھر حضرت رافع بن مالک ایک انصاری صحابی کو آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت عقبہ اولیٰ کے وقت
سورۃ یوسف کا مسودہ مدینہ کے مسلمانوں کے لیے عطا فرمایا تھا.بعد میں بھی حضرت رافع کچھ عرصہ کے لیے
رسول کریم کی خدمت میں رہے.اس اثناء میں سورۃ طہ نازل ہوئی اور اس کا مسودہ بھی ساتھ لے کر مدینہ منورہ
گئے.(اسد الغابہ زیر حالات حضرت رافع بن مالک بن عجلان )
پھر ہجرت کا مشہور واقعہ اس حقیقت کا ثبوت ہے کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی وحی کے ممکنہ نزول
کے پیش نظر سفر و حضر میں بھی سامان تحریر اپنے پاس رکھا کرتے تھے.ہجرت جیسے موقع پر جبکہ جان کو خطرہ تھا اور
دشمنوں کے نرغے سے نکل کر مدینہ پہنچنا بظاہر ناممکن دکھائی دیتا تھا، آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم سامان تحریر ساتھ لے
کر چلے.چنانچہ جب سراقہ بن مالک تعاقب کرتا ہوا آپ کے قریب آ پہنچا اور الہی تائید آپ کے شامل حال
دیکھ کر آپ سے امان کا طالب ہوا اور درخواست کی :
ان يكتب لي كتاب امن فامر عامر بن فہیرہ فكتب في رقعة من
(بخاری کتاب المناقب باب هجرة النبي و اصحابه الى المدينة)
ادیم
کہ مجھے پروانہ امن دے دیا جائے.اس پر آپ نے عامر بن فہیرہ کو حکم دیا اور انہوں نے
چمڑے کے ایک ورق پر مجھے پروانہ امن لکھ دیا
پس سراقہ بن مالک کی درخواست پر یکا یک اس صحرائے لق و دق میں سامان
تحریر مہیا ہو جانا اس بات کا
کس قدر واضح اور بڑا ثبوت ہے کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم خطر ناک سے خطرناک حالات میں بھی وحی الہی کی
کتابت کے خیال سے غافل نہ ہوتے تھے.اس واقعہ سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ مخالفین میں بھی یہ بات مشہور و معروف
تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامان تحریر اپنے پاس رکھتے ہیں تبھی تو سراقہ نے درخواست کی.
Page 35
عہد نبوی میں جمع و تدوین قرآن
19
ان سب واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ ابتدائی زمانہ سے ہی قرآن کریم تحریری صورت میں محفوظ کیا جاتا رہا
تھا اور جہاں جہاں مسلمان موجود ہوتے وہاں وہاں علاوہ درس و تدریس کے وحی الہی کی تحریری صورت میں
اشاعت ہوتی تھی.اس بات کے دلائل تو بہت ہیں کہ بعد کے زمانہ میں جب کہ اسلام کمزوری کی حالت سے نکلا
تو اس وقت قرآن کریم کے بہت سے نسخہ جات موجود تھے.نیز یہ کہ کتابت قرآن کا یہ کام رسول کریم صلی اللہ علیہ
والہ وسلم کے زیر نگرانی ہوتا تھا.ذیل میں چند روایات بطور نمونہ درج کی جاتی ہیں....لما نزلت لَا يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرَ أُولِى الضَّرَرِ وَ الْمُجَاهِدُونَ
فِي سَبِيلِ الله قال النبي صلى الله عليه و سلم ادع الى زيد او ليجئ باللوح
و القلم والكتف او الكتف والدواة ثم قال اكتب لا يستوى.....(بخاری کتاب التفسير باب قوله تعالى لايستوى القاعدون)
یعنی جب آیت لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرَ أُولِى الضَّرَرِ وَ
الْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ “ ( النساء : 96) نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے زید کو
بلا بھیجا اور وہ لوح اور قلم اور (اونٹ کے) شانہ کی ہڈی کے ساتھ یا راوی کا خیال ہے کہ شانہ کی
ہڑی یا دوات کے ساتھ تشریف لائے تو آپ نے فرمایا لکھو لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ
الْمُؤْمِنِينَ غَيْرَ أُولِى الضَّرَرِ وَ الْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا واضح ارشاد موجود ہے کہ فلا يـمـــس الـقـرآن انسان الا و هو
66
طاھر یعنی پاک آدمی کے سوا قر آن کو کوئی بھی نہ چھوئے.اسی طرح روایت ملتی ہے کہ:
عن عبد الله بن عمر قال نهى رسول الله ﷺ ان يسافر بالقرآن الى ارض العدو
(مسلم كتاب الامارة باب النهى ان يسافر بالفصحف الى ارض الكفار....)
حضرت عبد اللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا
ہے کہ اپنے ساتھ نسخہ قرآن لے کر دشمن کی سرزمین میں سفر کیا جائے.اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کو اس بات کا شوق تھا کہ سفر و حضر میں ان کے پاس خدا کا کلام لکھا ہوا
موجود ہو جسے وہ پڑھتے رہیں اور ہر وقت حتی کہ حالت جنگ میں بھی نسخہ قرآن اپنے ساتھ رکھنا چاہتے تھے.کتابت قرآن کا مزید ثبوت کا تب وحی حضرت زید بن ثابت کی اس روایت سے ملتا ہے.آپ فرماتے ہیں:
عن زيد بن ثابت قال كنا عند النبي ﷺ نؤلف القرآن من الرقاع
(ترمزی کتاب المناقب عن رسول الله باب في فضل الشام و اليمن)
(الاتقان: الجزء الاول ؛ النوع الثامن عشر ؛ جمع القرآن و ترتيبه ، صفحه:58)
(تفسير روح المعانى جزء اول صفحه 21 مكتبه امدادیه ملتان)
Page 36
الذكر المحفوظ
20
ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے زیر نگرانی کپڑے یا چمڑے کے ٹکڑوں پر قرآن کریم
تحریر کیا کرتے تھے.پھر بخاری میں ایک روایت ہے جس میں حضرت ابو بکر حضرت زید بن ثابت سے فرماتے ہیں:
نیز آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے کاتب وحی بھی تھے.اس لیے میرا خیال ہے
کہ آپ ہی یہ کام کریں کہ مختلف چیزوں پر لکھے ہوئے حصہ ہائے قرآن کو تلاش کریں اور
سارے قرآن کو ایک جگہ جمع کر دیں.اس پر حضرت ابوبکر نے مجھ سے مسلسل اتنا اصرار کیا کہ
آخر خدا نے مجھے بھی اس معاملہ میں شرح صدر عطا فرمایا جس بارہ میں حضرت ابوبکر و عمر (رضی
اللہ عنھما) کو شرح صدر عطا فر مایا تھا.تب میں نے مختلف جگہوں اور چیزوں سے قرآن کی آیات
جمع کیں جو کھجور کی ٹہنی کی ڈنٹھل اور پتھر کی باریک سلوں اور لوگوں کے سینوں میں محفوظ تھیں.(بخاری کتاب فضائل القرآن باب جمع القرآن
اس روایت سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتابت قرآن کریم کا خاص اہتمام فرماتے
اور اس مقصد کے لیے با قاعدہ کا تین مقرر تھے اور آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت سارا قرآن کریم
تحریری صورت میں محفوظ تھا.آنحضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا ایک ارشاد یہ ملتا ہے:
لا تكتبوا عنّى شيئا سوى القرآن
(مسند احمد بن حنبل؛ الباقى مسند المكثرين : مسند ابی سعید الخذری)
یعنی مجھ سے قرآن کے علاوہ کچھ نہ لکھا کرو.اسی طرح فرمایا:
لا تكتبوا عنى و من كتب عنى غير القرآن فلیمحه
(مسلم كتاب الذهد باب التثبت في الحديث و حكم كتابة العلم)
حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا کہ میرے
حوالہ سے کوئی چیز نہ لکھا کرو اور اگر کسی نے قرآن کے علاوہ کچھ اور لکھا ہو تو اس کو مٹادے.یہ روایت بھی جہاں کتابت وحی قرآن کو بیان کرتی ہے وہاں وحی قرآن کو ہر دوسری چیز سے جدا، ممتاز اور
پاک رکھنے کی مساعی پر بھی خوب روشنی ڈالتی ہے.اس سے ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ میں قرآن کریم تحریر کرنے کا
عام رواج تھا اور اس خطرہ کے پیش نظر کہ کہیں آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات قرآن کریم کی آیات کے
ساتھ مل جل نہ جائیں آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت فرمائی.چنانچہ صحابہ نے اس نصیحت پر بھی لبیک کہا.حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:
Page 37
عہد نبوی میں جمع و تدوین قرآن
21
مَا كَتَبْنَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا الْقُرْآنَ وَ مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ
(صحیح بخارى كتاب الجزية باب اثم من عاهد ثم غدر
”ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوائے قرآن کے اور جو کچھ اس صحیفہ میں ہے،
اور کچھ نہیں لکھا“
اسی طرح فرماتے ہیں
مَا عِنْدَنَا كِتَابٌ نَقْرَؤُهُ إِلَّا كِتَابِ اللهِ غَيْرَ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ
(صحيح بخارى كتاب الفرائض باب اثم من تبرا مواليه)
ہمارے پاس پڑھنے کے لیے سوائے صحیفہ خداوندی اور اس کتاب کے اور کوئی کتاب نہ تھی
اسی طرح رسول
کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی ملتا ہے کہ:
جو شخص پسند کرتا ہے کہ اسے اللہ اور اس کے رسول کی محبت حاصل ہو جائے تو اسے چاہیے کہ
66
قرآن مجید مُصْحَف “ سے دیکھ کر پڑھے.(الاتقان في علوم القرآن الجزء الاول صفحه 110)
حضرت اوس ثقفی سے یہ حدیث مروی ہے کہ:
زبانی قرآن پڑھنے کا ایک ہزار درجے ثواب ہے اور دیکھ کر پڑھنے کا ثواب اس سے
دو ہزار درجے تک زیادہ ہے.(البرهان في علوم القرآن جزء اول صفحه 462)
مندرجہ بالا تمام احادیث بالواسطہ یا بلا واسطہ طور پر بیان کر رہی ہیں کہ ابتداء اسلام سے ہی قرآن مجید تحریر کیا
جاتا تھا اور بہت سے صحابہ کرام کے پاس قرآن کریم کا کچھ نہ کچھ حصہ تحریری صورت میں ضرور موجود رہتا تھا جو
کتابت وحی قرآن
کا نا قابل تردید ثبوت ہے.اس کا ایک ثبوت
تعلیم القرآن کے باب میں قاری کو ملے گا کہ کس
طرح وسیع پیمانے پر تعلیم القرآن کی باقاعدہ کلاسز ہوا کرتی تھیں اور قرآن کریم کے کافی نسخہ جات نہ ہوں تو اس
طرح وسیع پیمانہ پر یہ کلاسز منعقد کرنا ناممکن تھا.کاتبین وحی
آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص چند صحابہ کو کتابت وحی قرآن کے لیے مقر فر مایا ہوا تھا.صحیح بخاری
میں درج حضرت انس رضی اللہ عنہ کی دوروایات کے مطابق ان میں سے انصار صحابہ کی تعداد پانچ تک بیان ہوئی
ہے.یعنی حضرت معاذ بن جبل، حضرت زید بن ثابت، حضرت ابوزیڈ اور حضرت ابودرداء.دوسری روایت
میں حضرت ابو درداء کی جگہ حضرت ابی بن کعب کا نام ملتا ہے.(بخاری کتاب فضائل القرآن باب القراء من اصحاب النبى علـ
لله الله
Page 38
الذكر المحفوظ
22
اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف یہی صحابہ قرآن کریم کی وحی کو نزول کے ساتھ ساتھ تحریر کیا کرتے تھے.بلکہ اور
بھی بہت سے صحابہ تھے جن کا تاریخ اسلام نے بطور خاص کتابت وحی قرآن کے حوالہ سے ذکر کیا ہے.مشہور
کاتبین میں خلفاء راشدین ، حضرت زبیر بن العوام ، حضرت شرجیل بن حسنہ ، حضرت عبداللہ بن رواحہ، حضرت
ابی بن کعب اور حضرت زید بن ثابت شامل ہیں.ان میں سے حضرت زید رضی اللہ عنہ تو آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم
کے خاص کا تب وحی تھے.لیکن ان کے ساتھ اور کا تین کی بھی آنحضور نے ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی.روایت ہے:
اذا نزل عليه شيء دعا بعض من كان يكتب
(مسند احمد بن حنبل؛ مسند عشرة المبشرين بالجنة مسند عثمان بن عفان
یعنی جب کوئی آیت نازل ہوتی تو آنحضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم ان میں سے کسی کو بلا لیتے
جو لکھنے پر مامور تھے.یہ بھی یا درکھنا چاہیے کہ بہت سے صحابہ ذاتی طور پر قرآن کریم تحریر کیا کرتے تھے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ و
الہ وسلم کے حضور پیش کر کے اپنے اپنے نسخہ کے مستند ہونے کو یقینی بناتے.عمدۃ القاری میں ہے:
پہلے کا تب وحی عبداللہ بن ابی سرح تھے.یہ بعد میں مرتد ہو گئے تھے اور فتح مکہ کے موقع پر
دوبارہ اسلام قبول کر لیا اور قرآن کے کاتبین میں خلفاء اربعہ کے علاوہ زبیر بن عوام، سعید بن
عاص بن امیہ کے دو بیٹے خالد اور ابان، حنظلہ بن ربیع الاسدی، معیقیب بن ابی فاطمہ، عبداللہ
بن ارقم زہری ، شرجیل بن حسنہ اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہم شامل ہیں.اور مدینہ میں جن
لوگوں نے وحی قرآن کو لکھنے کا کام کیا ان میں اُبی بن کعب اور اس سے پہلے کے کاتب وحی زید بن
ثابت شامل ہیں اور بھی بہت سے لوگ ان کے ساتھ شامل ہیں.(عمدة القارى شرح بخاری جلد 20 كتاب فضائل القرآن باب جمع القرآن صفحه 19)
تاریخی حقائق کی روشنی میں عبداللہ بن ابی سرح کو پہلا کاتب وحی لکھنا درست نہیں.کیونکہ یہ ابتدائی مومنین
میں سے نہیں ہیں بلکہ ان سے قبل کئی کبار صحابہ جولکھنا پڑھنا جانتے تھے ایمان لا چکے تھے.ان میں حضرت
ابو بکر،
حضرت علی، اور حضرت عثمان وغیرہ شامل ہیں.پس پہلا کاتب وحی ان ابتدائی مومنین میں سے ہی کوئی ہے.اس روایت میں پندرہ معین اصحاب کا ذکر ہے.تاریخ طبری میں دس اصحاب کے نام دیئے گئے ہیں جن میں
سے آٹھ مندرجہ بالا فہرست میں سے ہیں اور بقیہ دو حضرت علاء بن حضرمی اور معاویہ بن ابی سفیان کے نام ہیں.تاريخ الامم والملوك تاريخ طبرى جزء ثانی صفحه (421)
پھر عرض الانوار میں تاریخ طبری ، صحاح ستہ اور طبقات ابن سعد کے حوالہ سے کاتبین وحی کی ایک لمبی
Page 39
23
عہد نبوی میں جمع و تدوین قرآن
فہرست دی گئی ہے جس میں مندرجہ بالا سترہ (17) اصحاب کے علاوہ مزید گیارہ (11) اصحاب حضرت عبداللہ
بن سعد ، خالد بن ولید، محمد بن مسلمہ ، عبداللہ بن عبد اللہ بن ابی بن سلول ، مغیرہ بن شعبہ، عمرو بن العاص، جہم بن
صلت ، ثابت بن قیس بن شماس ، حذیفہ بن یمان ، عامر بن فہیرہ اور سعید بن جبیر رضی اللہ عنہم کے نام شامل ہیں.( عرض الانوار صفحہ 41 42 43 از قاضی عبد الصمد سیوہاروی مطبوعہ حمید برقی پریس دہلی.سن
اشاعت 1359 طبع اوّل)
اس طرح صرف ان تین روایات کو جمع کیا جائے تو کل 128 ایسے معین اصحاب کے نام ثابت ہوتے ہیں جن کو
بطورِ خاص کتابت وحی کی سعادت نصیب ہوئی.محققین خاص طور پر قرآن کریم کی کتابت کرنے والے صحابہ کرام
رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعداد چالیس تک بیان کی ہے.عام طور پر تو بہت سے صحابہ ذاتی طور پر قرآن کریم کے
نسخے تحریر کیا کرتے تھے.کاتبین کی تعداد کا اختلاف کوئی ایسا تاریخی اختلاف نہیں کہ جس میں ایک محقق ایک صحابی کے کاتب وحی
ہونے کا قائل ہے اور دوسرا محقق اس صحابی کے کاتب وحی ہونے کا قائل نہیں.بلکہ جس محقق کو تحقیق کے بعد جتنے
کاتبین صحابہ کا علم ہوا اس نے ان کے نام درج کر دیے اور جن صحابہ کا اُسے علم نہ ہوا ان کے نام دوسرے محققین
نے درج کر دیے.اُس دور میں رابطہ کی ایسی سہولیات تو میسر نہیں تھیں جیسی آج ہیں کہ ہر محقق کو ہر کا تب کا علم
ہوسکتا اور پھر فاصلے زیادہ ہونے کی وجہ سے ایک محقق دوسرے محققین اور علماء کی تحقیقات سے اس طرح فائدہ بھی
نہیں اُٹھا سکتا تھا جس طرح آج کے دور میں اُٹھایا جاتا ہے.ان صحابہ کے علاوہ بہت سے دیگر صحابہ کے مصاحف مشہور ہیں اور عام طور پر صحابہ کے پاس قرآن کریم کے
نسخہ جات بہت عام تھے.کسی کے پاس کچھ سورتیں لکھی ہوتیں اور کسی کے پاس کچھ صحابہ اپنی اپنی ضرورت،
علمیت اور شوق و اخلاص کے مطابق بھی قرآن جمع کرتے مثلاً حضرت عائشہ(بخاری فضائل القرآن باب
تاليف القرآن ).بعض صحابہ اپنے صحائف میں وہ سورتیں درج نہ کرتے جو انکو حفظ ہوتیں اور وہ سورتیں درج
کرتے جو حفظ نہ ہوتیں.اس طرح ایک کی لکھی ہوئی سورتیں دوسرے صحابی کے نسخہ میں موجود نہ ہوتیں بلکہ اس
صحابی کے پاس اس کے علم اور ضرورت کے مطابق دوسری چند سورتیں ہوتیں (بخاری کتاب فضائل
القرآن باب تعليم الصبیان القرآن.پھر بعض صحابہ نے بعض آیات کی تفسیر میں آنحضور صلی اللہ علیہ و
الہ وسلم سے کچھ سنا ہوتا تو انہیں بطور حاشیہ اپنے صحیفہ میں درج کرلیتے اور یہ علم ہوتا کہ یہ حصہ متن قرآن نہیں ہے
بلکہ حاشیہ ہے اور عام علم میں بھی یہ بات ہوتی کیونکہ اکثر لوگوں کو قرآن حفظ تھا اور خلط ملط ہونے کا کوئی خطرہ
نہیں تھا.لیکن پھر بھی آنحضور نے حفاظت قرآن کے ضمن میں کمال احتیاط کا نمونہ دکھاتے ہوئے اپنے فرمودات
لکھنے سے منع فرما دیا تا کہ خلط ہونے کا شائبہ بھی ختم ہو جائے.خلاصہ یہ کہ کبار صحابہ کے پاس ذاتی طور پر تحریر کیے
Page 40
الذكر المحفوظ
24
ہوئے قرآن کے نسخہ جات موجود تھے، اور بے شمار صحابہ کے پاس اپنے اپنے نسخہ جات موجود تھے جو فی ذاتہ تو نامکمل
تھے مگر مجموعی طور پر ان میں سارا قرآن
لکھا ہوا تھا.عہد نبوی میں کتابت قرآن کا طریقہ اور ذرائع
عہد نبوی میں عرب میں کاغذ بہت کم دستیاب تھا اور عام طور پر دسترس سے بھی باہر تھا.اس لیے قرآن کی وحی
کاغذ پر بہت کم لکھی گئی.اکثر حصہ عربوں کے دستور کے مطابق اس مقصد کے لیے مروج مختلف چیزوں پر لکھا
گیا.ان اشیاء کے نام کسی ایک جگہ اکٹھے نہیں ملتے.بخاری، الاتقان، کتاب المصاحف، عمدۃ القاری اور دیگر
کتب میں جو روایات جمع کی گئی ہیں ان سے مندرجہ ذیل نام ملتے ہیں.ا.کھجور کی شاخ کے ڈنٹھل
۲.باریک سفید پتھر کی سلیں.۳.اونٹ کے شانہ کی ہڈیاں
۴.اونٹ کی پسلی کی ہڈیاں
۵.اونٹ کی کاٹھی کی لکڑیاں.لکڑی کی تختیاں
ے.چمڑے کے ٹکڑے
۹.پتلی جھلی..کھال
۱۰.کاغذ
گزشتہ صفحات میں روایات درج کی جاچکی ہیں جن سے یہ نتائج اخذ ہوتے ہیں کہ جونہی کوئی آیت نازل
ہوتی حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم فوری طور پر کسی کا تب و بلا کر لکھوا دیتے.کاتبین وحی جب آیت لکھ
لیتے تو آپ پہلے پڑھوا کے سنتے چنانچہ زید بن ثابت کا بیان ہے کہ فان كــان فـيـه سقط اقامه ، یعنی اگر
کوئی غلطی ہوتی تو اس کی تصحیح کروا دیتے اور حفظ پر مقر صحابہ کو فورا اپنی نگرانی میں حفظ کروا دیتے جو آگے دیگر صحابہ کو
حفظ کرواتے اور یہ سلسلہ چلتا رہتا.صحابہ کرام کثرت کے ساتھ فوری طور پر نئی آنے والی وحی کو حفظ کر لیتے اور
اپنے اپنے ذاتی صحائف میں درج کر لیتے اور پھر اپنا حفظ اور اپنی تحریرات رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی
خدمت میں پیش کر کے اُن کی درستگی کی سند حاصل کرتے اور پھر صحابہ کثرت تلاوت سے اور گاہے گا ہے ایک
دوسرے کے سامنے اپنا حفظ پیش کر کے اپنے اور دوسرے صحابہ کے حفظ کی حفاظت کرتے.آنحضور صلی اللہ علیہ
وسلم بھی وقتافوقتاً صحابہ سے قرآن کریم سنتے رہتے.عبید نبوی میں قرآن کریم مکمل طور پر تحریری صورت میں جمع ہو چکا تھا
یہ بات بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ کتابت قرآن پر مقرر صحابہ نے اپنا فرض ادا کرتے ہوئے نزول کے
ساتھ ساتھ تحریر کرتے ہوئے مکمل قرآن مجید کے نسخہ جات تیار کر لیے تھے جو اپنی جگہ جمع قرآن کا ایک اہم باب
Page 41
عہد نبوی میں جمع و تدوین قرآن
25
ہے.اس سلسلہ میں صحیح بخاری کی روایت ہے.حضرت انس انصار کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:
حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَنْ جَمَعَ الْقُرْآنَ
عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَرْبَعَةٌ كُلُّهُمْ مِنْ الْأَنْصَارِ أُبَيُّ
بْنُ كَعْب وَمُعَاذُ بْنُ جَبَل وَزَيْدُ بْنُ ثَابت وَأَبُو زَيْد تَابَعَهُ الْفَضْلُ عَنْ
حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدِ عَنْ تُمَامَةَ عَنْ أَنَسٍ
” قتادہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک سے ان لوگوں کے بارہ میں پوچھا
جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نگرانی میں قرآن کریم کو جمع کیا.آپ نے فرمایا.چار
آدمی ہیں جو کہ سارے انصاری ہیں.اُبی بن کعب، معاذ بن جبل ، زید بن ثابت اور ابوزید.پھر اس سے اگلی روایت میں ہے کہ:
حَدَّثَنِي ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ وَتُمَامَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ مَاتَ النَّبِيُّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَحْمَعْ الْقُرْآنَ غَيْرُ أَرْبَعَةِ أَبُو الدَّرْدَاءِ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ
وَزَيْدُ بْنُ ثَابِت وَأَبُو زَيْد قَالَ وَنَحْنُ وَرِثْنَاهُ
(بخاری کتاب فضائل القرآن باب القراء من اصحاب النبى
صلى الله
حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی وفات کے وقت تک چار
66
اشخاص نے قرآن کریم کو جمع کیا تھا.ابو درداء، معاذ بن جبل ، زید بن ثابت اور ابوزید
حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ان دونوں روایتوں میں تین نام حضرت معاذ بن جبل، حضرت زید بن ثابت اور
حضرت ابوزید مشترک ہیں اور ایک روایت میں حضرت ابو درداء اور دوسری روایت میں حضرت ابی بن کعب کا
نام ہے.اس طرح صرف ان دو روایتوں کو جمع کرنے سے انصار میں سے صرف حضرت انس" کے قبیلہ سے ہی
پانچ اصحاب النبی صلی اللہ علیہ والہ وسلم ایسے ثابت ہوتے ہیں جنہوں نے پورا پورا قرآن مجید جمع کیا ہوا تھا.علامہ ذہبی نے طبقات القراء میں لکھا ہے:
علامہ ابن سعد نے بھی طبقات قسم ثانی جلد 2 ص 112 میں بعض ایسے صحابہ کے نام شمار کیے
ہیں جنہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی حیات مبارکہ میں پورا قرآن جمع کیا تھا.( بحوالہ جمع و تدوین قرآن از سید صدیق حسن صاحب مطبع معارف لکھنو 1964 صفحہ 13 )
پھر صحابہ کے متفرق نسخے موجود تھے جن میں مجموعی طور پر مکمل قرآن کریم موجود تھا جیسے حضرت عبد اللہ بن
مسعود رضی اللہ عنہ نے قرآن کی بہت سی سورتیں ترتیب نزولی کے مطابق جمع کی تھیں.(بخاری فضائل
القرآن باب تاليف القرآن ( حضرت ابن عباس نے بھی قرآن کریم کا ایک نسخہ لکھا تھا جس میں چند سورتیں
Page 42
الذكر المحفوظ
26
تھیں (بخاری کتاب فضائل القرآن باب تعليم الصبيان القرآن ).حضرت عائشہ نے قرآن
کریم کا ایک نسخہ جمع کیا ہوا تھا (بخاری فضائل القرآن باب تاليف القرآن ) کتاب المصاحف میں
دیگر امہات المؤمنین کے صحائف کا بھی ذکر ہے.مشہور شیعہ تفسیر مجمع البیان میں علامہ طبرسی حفاظت قرآن کا ذکر کرتے ہوئے اپنا عقیدہ بیان کرتے ہیں کہ
قرآن
کریم بعینہ محفوظ ہے جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا اور وہی تحریر ایک تو اتر کے ساتھ ہم
تک پہنچی ہے اور اپنی تائید میں ایک حوالہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں:
و كذالك القول في كتاب الـمـزنـي.....ان القرآن كان على عهد
رسول الله (ص) مجموعا مؤلفا على ما هو عليه الان
(ابوالفضل بن الحسن الطبرسي: مجمع البيان الجزء الاول: الفن الخامس صفحه 15
الناشر مكتبه علميه الاسلاميه (ملتان)
یعنی یہی بات علامہ مزنی بھی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں...کہ قرآن رسول کریم کے دور میں
ہی جمع ہو گیا تھا اور اسی طرح تالیف ہو گیا تھا جیسا کہ آج کے دور میں ہے.نامی گرامی مستشرق بھی کھلے دل سے یہ اعتراف کرتے ہیں کہ قرآن کریم رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی
نگرانی میں ہی مکمل طور پر تحریری صورت میں محفوظ کر لیا گیا تھا.آج تک یہ غیر مبدل اور غیر محرف ہے اور محفوظ
حالت میں ہم تک پہنچا ہے اور بالفاظ میور ” ہمارے پاس ہر ایک قسم کی ضمانت موجود ہے، اندرونی شہادت کی
بھی اور بیرونی کی بھی کہ یہ کتاب جو ہمارے پاس ہے، وہی ہے جو خود محمد ( صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے دنیا کے
سامنے پیش کی تھی اور اسے استعمال کیا کرتے تھے.“ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرنے والے محققین ہر دور میں یہ
گواہیاں دیتے چلے آئے ہیں.جن کا ذکر اپنے مقام پر قاری کو ملے گا.آج حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ
وسلم کے دور کا تحریر کردہ کوئی بھی مکمل نسخہ قرآن موجود نہیں ہے.اس کی بنیادی وجہ حضرت عثمان کا حفاظت قرآن
کے حوالہ سے کیا گیا ایک اہم فیصلہ ہے.آپ نے اپنے دور میں تمام سابقہ نسخوں کو تلف کر کے اجماع امت سے
جمع کیے ہوئے قرآن پر امت کو اکٹھا کر دیا تھا.اب ذرا غور کیجیے کہ ابن وراق
کا یہ کہنا کہ محمد (ﷺ) کی وفات 632ء کے بعد آپ کی وحی کا کوئی مجموعہ
موجود نہیں تھا.کتنا بڑا جھوٹ ہے.تاریخ مذاہب میں قرآن کریم ہی وہ واحد اور اکلوتی کتاب ہے کہ جس کے
بارہ میں ثابت ہے کہ جس نبی پر نازل ہوئی، اسی نبی کی موجودگی میں، اسی نبی کی نگرانی میں، حفاظت کے تمام تر
تقاضے پورے کرتے ہوئے تحریر اور حفظ کے ذریعہ محفوظ کی گئی اور کثرت سے اس کی اشاعت بھی کی گئی.سوال یہ ہے کہ جب بنیاد ہی جھوٹی ہے تو پھر اس کے سہارے قرآن کریم کے غیر محفوظ ثابت کرنے کی جو
Page 43
عہد نبوی میں جمع و تدوین قرآن
27
مذموم کوشش ابن وراق کر رہا ہے، اس کی کیا حقیقت رہ جاتی ہے؟ جھوٹی بنیاد اور غلط نتیجہ بہر حال اس جھوٹ
کے ثابت ہونے کے بعد بھی ہم ابن وراق کی اس خواہش کو کہ قرآن کریم کی تاریخ کو دوبارہ کھنگالنے کی ضرورت
ہے، پورا کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں.حفظ قرآن کریم
حفاظت قرآن کے باب میں ایک بے نظیر اور اہم طریقہ حفظ قرآن کریم ہے جو امت مسلمہ میں پہلی آیت
کے نزول سے لے کر آج تک رائج ہے.یہ طریقہ بظاہر تو انسانی ذرائع میں سے ایک معلوم ہوتا ہے مگر ادنی سے
تدبر سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ حفظ قرآن بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے امت محمدیہ کو حفاظت قرآن کے
باب میں ایک بے نظیر الہی عطا ہے.اگر یہ انسانی طاقت میں ہوتا تو دوسرے مذاہب اپنی اپنی کتب کو محفوظ رکھنے
کے لیے ضرور اس طریقہ کو استعمال کرتے.مگر صرف قرآن کریم کو یہ خصوصیت حاصل ہونا اس بات کا ثبوت ہے
کہ اس کتاب کی حفاظت کے لیے یہ خدا تعالیٰ نے اپنی جناب سے یہ خاص انتظام فرمایا تھا.اگر ایسا انتظام انسانی
طاقت میں ہوتا تو لازماً اور بھی مثالیں ملتیں.حضرت مرزا بشیرالدین محموداحمد صاحب خلیفہ اسی الثانی الصلح الموعودرضی اللہ عہ فرماتے ہیں:
یہ بھی یادر ہے کہ ایسے آدمیوں کا میسر آجانا جو اسے حفظ کرتے اور نمازوں میں پڑھتے
تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی طاقت میں نہ تھا.ان کا مہیا کرنا آپ کے اختیار سے باہر
تھا.اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِكرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ (الحجر:10) که
ایسے لوگ ہم پیدا کرتے رہیں گے جو ا سے حفظ کریں گے.آج اس اعلان پر تیرہ سوسال
ہو چکے ہیں اور قرآن مجید کے کروڑوں حافظ گزر چکے ہیں.“
( تفسیر کبیر جلد چہارم زیر تفسیر المجر آیت 10 صفحہ 15)
پس قرآن کریم کی کامل حفاظت کے لیے حفظ قرآن کا بے مثل وسیلہ خالصۂ الہی عطا ہے.ابتدا سے ہی رسول
کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم وحی الہی تحریر کروانے کے بعد سنتے اور پھر تسلی کرنے کے بعد آپ صحابہ کو حفظ کراتے
اور پھر اسکی اشاعت ہوئی.آپ نے چند صحابہ کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی جن کا کام تھا کہ وہ پہلے خود آنحضور سے
قرآن کریم حفظ کر لیں اور پھر دیگر صحابہ کو حفظ کروائیں.چنانچہ روایات میں حضرت عبد اللہ بن مسعود حضرت
سالم حضرت ابی بن کعب اور حضرت معاذ بن جنبل رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسے کبار صحابہ کے نام ملتے ہیں.(بخاری کتاب فضائل القرآن باب جمع القرآن ) یہ ذکر بھی ملتا ہے کہ بہت سے جانثار صحابہ فوری
طور پر قرآن کریم کی تازہ بتازہ نازل ہونے والی وحی کو بلا توقف حفظ کرلیا کرتے تھے.حضرت رسول کریم صلی
Page 44
الذكر المحفوظ
دو
28
اللہ علیہ والہ وسلم بھی حفظ قرآن کی فضیلت پر بہت زور دیتے تھے.اس میں تو کوئی شک نہیں کہ خدا تعالیٰ نے آپ
کو صحابہ کی ایسی جماعت عطا فرمائی تھی جو آپ کے ہر اشارہ پر عمل کرنے کے لیے جان توڑ کوشش کرتے تھے اور
جان کی بازی لگانے سے بھی دریغ نہیں کرتے تھے.اس لیے آپ کی اس تحریک اور خواہش کی تکمیل کے لیے
صحابہ نے حیرت
انگیز نمونہ دکھایا.قرآن کریم بکثرت حفظ کیا جانے لگا.صحابہ نے اس وارفتگی اور اس شان سے
اپنے آقا کی آواز پر لبیک کہا کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں حفاظ صحابہ کی اتنی کثیر تعداد تیار ہوگئی
کہ بلا مبالغہ ہزاروں تک ان کی تعداد جا پہنچتی ہے.کیا بچے کیا جو ان اور کیا بوڑھے ، کیا عورتیں اور کیا مرد،سب
حفظ قرآن کے میدان میں بڑھ چڑھ کر عشق و محبت اور اخلاص و فدائیت کے بے نظیر جذبات کے ساتھ معرکے سر
کرنے لگے.حفاظ صحابہ کی کثرت کا اندازہ اس واقعہ سے ہوتا ہے کہ ایک دفعہ غزوہ احد کے بعد قبیلہ رعل،
ذکوان ، عصیۃ اور بنو لحیان کے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے ایسا نمونہ دکھایا کہ سمجھا گیا کہ یہ لوگ مسلمان ہو چکے
ہیں.چنانچہ انہوں نے اپنی قوم کی تعلیم و تربیت کے لیے آنحضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے مدد کی درخواست کی.آپ نے اس درخواست کو شرف قبولیت بخشا اور صرف انصار مدینہ میں سے ستر (70) حفاظ وقراء کا ایک بڑا
گروہ روانہ کر دیا تا کہ ان کے قبیلوں کے لوگوں کو اسلام کی تعلیمات سے روشناس کروائیں.یہ حفاظ مدینہ
میں قراء کے نام سے مشہور تھے.ان لوگوں نے راستہ میں دھوکہ دے کر ان حفاظ کو شہید کر دیا (بــــــاری
كتاب الجهاد و السير باب العون بالمدد ) صرف انصار مدینہ میں سے ستر (70) حفاظ کا بھیجنا بتاتا ہے کہ
کثرت سے حفاظ موجود تھے اور تعلیم القرآن کے سلسلہ میں کثرت سے اساتذہ مختلف قبائل میں جاکر رہا کرتے
اور تعلیم و تدریس کے فرائض سرانجام دیتے تھے.چنانچہ اس واقعہ کے علاوہ اور بھی واقعات ملتے ہیں کہ رسول
کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم مختلف قبائل میں دس دس پندرہ پندرہ قراء صحابہ کے وفود تعلیم القرآن کے لیے بھیجا
کرتے تھے.آنحضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی وفات کے وقت حفاظ کی کثرت کا یہ حال تھا کہ صرف ایک جنگ
یعنی جنگ یمامہ میں شہداء میں صرف حفاظ شہداء کی تعداد سات سو (700) اور بعض کے نزدیک اس سے بھی زیادہ
تھی.چنانچہ بخاری کتاب فضائل القرآن باب جمع القرآن میں درج اس واقعہ کے بارہ میں بخاری کی ایک
معروف شرح عمدۃ القاری میں لکھا ہے:
ربیع الاول اا ھجری میں آنحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے اس دار فانی سے رحلت فرمائی
آپ نے وفات سے قبل تمام قرآن لکھوا دیا تھا مگر وہ مختلف چیزوں پر لکھا ہوا مختلف اصحاب کے
پاس بکھرا ہوا تھا.آنحضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر کا انتخاب بطور
خلیفہ اول ہوا اور ابتداء میں ہی آپ کو پے در پے مشکلات و مصائب کا سامنا کرنا پڑا.ان میں
Page 45
29
عہد نبوی میں جمع و تدوین قرآن
سے ایک زبر دست فتنہ جھوٹے مدعیان نبوت اور ان کی شورش و بغاوت کا تھا.اس سلسلہ میں
سب سے بڑا معرکہ مسیلمہ کذاب سے یمامہ کے مقام پر ہوا.اس معرکہ میں دونوں لشکروں کا
بھاری نقصان ہوا.شہید ہونے والے مسلمانوں میں سات سوقراء وحفاظ تھے اور بعض کے
نزدیک ان کی تعداد اس سے بھی زائد تھی.(عمدة القارى جلد 20 كتاب فضائل القرآن باب جمع القرآن صفحه 16)
حفظ کی یہ مبارک عادت امت میں آج تک پورے اہتمام کے ساتھ جاری ہے.حضرت مرزا بشیر الدین
محمود احمد صاحب خلیفہ اسیح الثانی اصلح الموعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:
کسی مضمون کی حفاظت بھی مکمل طور پر نہیں ہو سکتی جب تک وہ تحریر اور حفظ دونوں ذریعہ
سے محفوظ نہ کیا جائے.انسانی حافظہ بھی غلطی کر جاتا ہے اور کا تب بھی بھول چوک جاتا ہے لیکن
یہ دونوں مل کر ایک دوسرے کی غلطی کو نکال دیتے ہیں اور ان دوسامانوں کے جمع ہونے کے بعد
غلطی کا امکان باقی نہیں رہ سکتا.قرآن کریم کو یہ دونوں حفاظتیں حاصل ہیں.یعنی وہ کتاب بھی
ہے.رسول کریم صلعم کی زندگی سے ہی اس کے الفاظ تحریر کر کے ضبط میں لائے جاتے رہے ہیں
اور وہ قرآن بھی ہے.یعنی نزول کے وقت سے آج تک ہزاروں لوگ اسے حفظ کرتے اور اس
کی تلاوت کرتے چلے آئے ہیں.ایک محقق لکھتا ہے :
( تفسیر کبیر جلد 4 صفحه 5 زیرتفسير سورة الحجر :2)
Thus, if the Qur'an had been transmitted only orally
for the first century, sizeable variations between texts
such as are seen in the hadith and pre-Islamic poetry
would be found, and if it had been transmitted only in
writing, sizeable variations such as in the different
transmissions of the original document of the
constitution of Medina would be found.But neither is
the case with the Qur'an.There must have been a
parallel written transmission limiting variation in the
oral transmission to the graphic form, side by side with a
parallel oral transmission preserving the written
transmission from corruption.(Andrew Rippin (Ed),Approaches Of The History of Interpretation
Of The Qur'an, 1988, Clarendon Press, Oxford, p.44.)
اگر قرآن کریم صرف حفظ کے ذریعے آگے منتقل ہوتا تو اس میں ایسی تبدیلیاں ہوسکتی تھیں جیسی
احادیث اور دور جاہلی کی شاعری میں ہیں.اگر قرآن کریم صرف تحریری طور پر آگے منتقل ہوتا تو پھر
Page 46
الذكر المحفوظ
30
میثاق مدینہ کے نسخہ کی طرح اس کے بھی باہمی مختلف نسخے ہوتے.لیکن موجودہ صورت میں ایسا بالکل
بھی ممکن نہیں ہوا.حفظ کے متوازی متن کی تحریری صورت نے حفظ کی حفاظت کی اور اس میں تبدیلی
نہیں ہونے دی اور تحریر کے متوازی حفظ نے تحریر کی حفاظت کی اور اس میں تبدیلی نہیں ہونے دی.ایک طرف یہ حقیقت ہے اور دوسری طرف ایک حقیقت یہ ہے کہ عربوں کا حافظہ ایک مثالی حافظہ تھا.وہ لوگ
اپنے نسب نامے یا درکھتے اور ہزاروں ہزار شعر یا درکھتے تحریر کا رواج عام نہ ہونے کی وجہ سے حافظہ کی طاقت
کس قدر غیر معمولی طور پر بڑھ چکی تھی اس کی ایک مثال ملاحظہ کیجیے کہ رسول کریم کے ارشادلا تكتبوا عـنـى
سوی القرآن(مسند احمد بن حنبل الباقي مسند المكثرين مسند ابی سعید الخذری) تعمیل میں آپ کے
اقوال اور احادیث زیادہ تر حافظہ کی بنیاد پر یاد رکھی جاتی تھیں اور ان کے حفظ کا با قاعدہ انتظام نہیں تھا.صحابہ عشق
رسول صلی اللہ علیہ والہ وسلم میں ڈوبے ہونے کی وجہ سے آپ کے اقوال اور احادیث مختلف مواقع پر گھروں میں،
مجالس میں سفر وغیرہ پر ایک دوسرے کو سنتے سناتے اور اس طرح سینہ بسینہ آپ کے فرمودات ایک نسل سے
دوسری نسل کو منتقل ہوتے رہے اور آپ کی وفات کے سو ڈیڑھ سو سال بعد تحقیق کر کے تحریری صورت میں جمع
کر لیے گئے.جبکہ قرآن کریم نا صرف ساتھ ساتھ تحریر میں محفوظ کیا جاتا رہا بلکہ اس کے حفظ کا با قاعدہ اہتمام کیا
جاتا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم خود اس کی نگرانی فرماتے تھے.اب اس واقعہ پر نظر ڈالیں کہ حضرت
رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے شاہ مصر مقوقس کے نام ایک خط لکھوایا تھا.خط تو بادشاہ کی خدمت میں بھجوادیا گیا
مگر صحابہ نے اس کو بھی اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا اور اس طرح یہ سینہ بسینہ روایات کی صورت میں نسلاً بعد نسل
آگے منتقل ہوتا رہا.رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی وفات سے سو، ڈیڑھ سوسال کے بعد جب احادیث اکٹھی
کی گئیں تو اس خط کے بارہ میں روایات پر تحقیق کر کے راویوں کے سینوں میں محفوظ اس خط کے الفاظ کتب
حدیث میں درج کر لیے گئے.قریباً ایک سو سال قبل رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا لکھوایا ہوا اصل خط
دریافت ہو چکا ہے اور حیرت کی بات یہ ہے کہ دونوں خط ، یعنی دریافت شدہ اور کتب حدیث میں بزبان رواۃ
محفوظ خط حیرت انگیز طور پر ایک دوسرے کے عین مطابق ہیں.(حضرت مرزا بشیر احمد صاحب سيرة خاتم النبین
صفحہ 822) ایک خط کا سینہ بسینہ آگے منتقل ہونے والی روایات میں ذکر ہونا اور پھر سو دوسوسال کے بعد ان
روایات کا تحریری شکل میں آنا اور جب خط کی اصل تحریر دریافت ہوئی تو الفاظ تک میں مطابقت ہونا، یہ ثابت کرتا
ہے کہ عربوں کا حافظہ کتنا مثالی اور غیر معمولی تھا اور یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ کس درجہ امانت دار تھی وہ قوم کہ جس نے
رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے وہ الفاظ جو کہ وحی الہی نہیں تھے اس حفاظت کے ساتھ یادر کھے.تو سوچیے کہ
وہ قوم وحی الہی کو کس حفاظت سے رکھتی ہوگی.عربوں کے حافظہ کے غیر معمولی ہونے کا تمام محققین بہت واضح
Page 47
عہد نبوی میں جمع و تدوین قرآن
31
انداز میں ذکر کرتے ہیں.عربوں کا نسب نامے یادرکھنا، ایک ایک شخص کو ہزاروں ہزار شعر یاد ہونا، شعر وسخن کی
مجالس میں شعر سنانا وغیرہ بہت معروف پہلو ہیں.پس اس شان کے حافظہ کے ساتھ اس درجہ امانتدار لوگ قرآن
کو ایسی حالت میں حفظ کر رہے ہیں کہ عام نسب ناموں اور شعر و شاعری سے
کہیں زیادہ قرآن کریم کی اہمیت کو
تسلیم کرتے ہوئے اور محبت کو بنیاد بناتے ہوئے اس کے ایک ایک لفظ کو اپنی نجات کا سامان اور الہی امانت سمجھتے
ہیں جسے آگے منتقل کرنا اپنی اولین ذمہ داری گردانتے ہیں.پھر قرآن کریم تحریری صورت میں بھی موجود ہے.تو
کوئی بھی غلطی یا دانستہ تحریف کس طرح راہ پا سکتی ہے؟ پھر یہ بھی دیکھئے کہ روایات تو اس کثرت سے سنائی نہ جاتی
تھیں جس کثرت سے قرآن کریم کی درس و تدریس اور تلاوت ہوتی تھی.پس قرآن کریم کسی بھی صورت میں
بھلا دیا جائے یہ ناممکن ہے.رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک ایک ایسے تواتر کے
ساتھ حفاظ آئندہ نسل کو قرآن کریم حفظ کراتے چلے آئے ہیں جو آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوتا ہے اور
پھر قرآن کریم کی تحریر سے اپنے حفظ کو مستند بناتے چلے آئے ہیں.چنانچہ اس تواتر کے باقاعدہ اہتمام کا ذکر صحابہ
کے دور سے ملتا ہے.کثرت سے اس بارہ میں روایات ملتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم حفاظ صحابہ سے قرآن
کریم سنتے رہتے تھے.مثلاً:
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْرَأْ
عَلَيَّ الْقُرْآنَ قُلْتُ اقْرَأْ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ قَالَ إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ
غَيْري
(بخاری کتاب فضائل القرآن باب من احب ان يسمع القرآن من غيره)
حضرت ابن مسعودؓ بیان کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ مجھے
قرآن مجید سناؤ.میں نے حیران ہو کر عرض کیا کہ میں آپ کو قرآن سناؤں! حالانکہ قرآن آپ
پر نازل کیا گیا ہے.حضور نے فرمایا.دوسرے سے قرآن سننا مجھے بہت اچھا لگتا ہے.روایات کے مطابق صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک دوسرے کے حفظ کی نگرانی بھی کرتے رہتے.مثلاً :
عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ يَقْرَأُ سُورَةَ
الْفُرْقَانِ فِي حَيَاةِ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَمَعْتُ لِقِرَاءَتِهِ
فَإِذَا هُوَ يَقْرَأُ عَلَى حُرُوف كَثِيرَة لَمْ يُقْرتْنيهَا رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَكَدْتُ أُسَاوِرُهُ فِي الصَّلَاةِ فَتَصَبَّرْتُ حَتَّى سَلَّمَ فَلَبَّبْتُهُ بِرِدَائِهِ
فَقُلْتُ مَنْ أَقْرَأَكَ هَذه السُّورَةَ الَّتي سَمِعْتُكَ تَقْرَأُ قَالَ أَقْرَأَنِيهَا رَسُولُ
الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ كَذَبْتَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
Page 48
الذكر المحفوظ
32
وَسَلَّمَ قَدْ أَقْرَأَنِيهَا عَلَى غَيْرِ مَا قَرَأْتَ فَانْطَلَقْتُ بِهِ أَقُودُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتَ إِنِّي سَمِعْتُ هَذَا يَقْرَأُ بِسُورَةِ الْفُرْقَانِ عَلَى
حُرُوف لَمْ تُقْرتْنيهَا فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلْهُ اقْرَأْ
يَا هِشَامُ فَقَرَأَ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةَ الَّتِي سَمِعْتُهُ يَقْرَأُ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَلِكَ أُنْزِلَتْ ثُمَّ قَالَ اقْرَأْ يَا عُمَرُ فَقَرَأْتُ الْقِرَاءَةَ الَّتِي
أَقْرَأَنِي فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَلِكَ أُنْزِلَتْ إِنَّ هَذَا
الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَة أَحْرُفِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ
(بخاری کتاب فضائل القرآن باب انزل القرآن على سبعة حرف)
حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی زندگی میں ایک
صحابی ہشام بن حکیم بن حزام کو سورۃ الفرقان کی تلاوت کرتے ہوئے سنا.میں نے غور سے سُنا
تو معلوم ہوا کہ وہ کسی ایسے انداز میں پڑھ رہے ہیں جس انداز میں رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم
نے
کبھی مجھے نہیں پڑھایا.پس میں ان
کی نماز مکمل ہونے کا انتظار کرتارہا اور مجھے ان کی نماز کے
اختتام تک بہت صبر سے بیٹھنا پڑا.جب انہوں نے سلام پھیرا تو میں نے ان کو ان کی چادر سے
پکڑ لیا اور پوچھا کہ جو سورۃ میں نے ابھی تجھ سے سنی ہے یہ تجھے کس نے پڑھائی ہے.انہوں نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی ہے.میں نے کہا تم غلط کہتے ہو
کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھی پڑھائی ہے اور وہ اس طرح نہیں ہے.پس میں
انہیں لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ میں نے
انہیں قرآن کریم اس انداز میں پڑھتے ہوئے سُنا ہے جو آپ نے مجھے نہیں پڑھایا.اس پر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو اور کہا اے ہشام پڑھو! انہوں نے تلاوت
کی.پھر آپ نے مجھے پڑھنے کا ارشاد فرمایا پس میں نے اسی طرح تلاوت کی جس طرح میں
نے رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے سیکھی تھی.اس پر رسول کریم نے فرمایا کہ ( یہ سورت )
اس طرح بھی نازل ہوئی ہے.پھر فرمانے لگے کہ قرآن کریم سات حروف میں نازل ہوا ہے
پس جیسے آسانی محسوس کرو، پڑھ لیا کرو.ذیل میں نمونہ کے طور پر چند روایات درج کی جارہی ہیں.جن سے علم ہوتا ہے کہ آنحضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم
کس درجہ تاکید کے ساتھ صحابہ کو حفظ قرآن کی تلقین کیا کرتے تھے.
Page 49
عہد نبوی میں جمع و تدوین قرآن
33
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه و سلم يُقَالُ
لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ إِقْرَاءُ وَارْتَقِ وَرَتِّلُ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا فَإِنَّ
مَنْزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَؤُهَا.(سنن ابی داود کتاب الوتر باب استحباب الترتيل في القراءة)
حضرت عبداللہ بن عمر ورضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
که حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن کریم پڑھتا جا اور درجات میں ترقی کرتا جا اور عمدگی سے
پڑھ جیسے دنیا میں عمدگی سے پڑھتا تھا.تیرا مقام وہ ہے جس آیت پر تو قراءت کو ختم کرے گا.حضرت ابن عباس سے روایت ہے:
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُقَالُ
لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ إِذَا دَخَلَ الْجَنَّةَ اِقْرَأْ وَاصْعَدْ.فَيَقْرَأُ وَيَصْعَدُ بِكُلِّ آيَةٍ
دَرَجَةٌ حَتَّى يَقْرَأُ اخَرَ شَيْءٍ مَّعَهُ
(سنن ابن ماجه كتاب الادب باب ثواب القرآن من اختلاف الرواة)
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے
فرمایا کہ حافظ قرآن کو جنت میں داخل ہوتے وقت کہا جائے گا کہ تم قرآن پڑھتے جاؤ اور
بلندی کی طرف چڑھتے جاؤ.پس وہ قرآن کریم پڑھتا جائے گا اور بلندی کی منازل طے کرتا
جائے گا کیونکہ ہر ایک آیت کے بدلے اس کے لیے ایک درجہ ہوگا یہاں تک کہ آخری آیت
کے پڑھنے تک جو اسے یاد ہو گی وہ بلندی کی طرف چڑھتا جائے گا.عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه و سلم : إِنَّ الرَّجُلَ
الَّذِي لَيْسَ فِي جَوْفِهِ شَيْءٌ مِّنَ الْقُرْآنِ كَالْبَيْتِ الْخَرِبِ
(سنن الدارمی کتاب فضائل القرآن باب فضل من قرأ القرآن
حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص
جس نے قرآن کریم کا کوئی حصہ بھی حفظ نہیں کیا وہ ویران گھر کی طرح ہے.پھر آنحضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے حافظ قرآن کو حفاظت قرآن کے باب میں بھی خبر دار کیا کہ:
عَنْ عُثْمَانَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَوْسِ الثَّقَفِي عَنْ جَدِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قِرَاءَةُ الرَّجُلِ فِي غَيْرِ الْمُصْحَفِ أَلْفُ
Page 50
الذكر المحفوظ
34
دَرَجَةٍ وَ قِرَاءَ تُهُ فِي الْمُصْحَفِ تَضْعَفُ عَلَى ذلِكَ إِلَى الْفَى دَرَجَةٍ
(مشكاة المصابيح كتاب فضائل القرآن الفصل الثالث)
عبداللہ بن اوس تلفظی اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے
فرما یا کسی شخص کا زبانی قرآن کریم پڑھنا ایک ہزار درجہ کے برابر ہے اور قرآن کریم کو مصحف سے
دیکھ کر پڑھنا اسے دو ہزار درجہ تک بڑھاتا ہے.یہاں حافظ قرآن کو یہ نصیحت بھی فرما دی کہ ہمیشہ اپنے حافظہ پر ہی انحصار نہ کرے بلکہ وقتا فوقتا کتاب الہی
سے تلاوت کر کے اپنے حفظ کی درستگی یقینی بناتا ر ہے.پھر حافظ قرآن
کو با قاعدگی سے تلاوت قرآن کریم کرنے کی نصیحت کرتے ہوئے فرمایا:
عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ
وَهُوَ حَافِظٌ لَّهُ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ وَمَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَهُوَ
يَتَعَاهَدُ وَهُوَ عَلَيْهِ شَدِيدٌ فَلَهُ أَجْرَان - “
66
(بخارى كتاب التفسير تفسير سورة عبس)
ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے
فرمایا کہ وہ شخص جو قرآن کریم پڑھتا ہے اور اس کا حافظ ہے وہ ایسے لکھنے والوں کے ساتھ ہوگا
جو بہت معزز اور بڑے نیک ہیں اور وہ شخص جو قرآن کریم کو پڑھتا ہے اور اس کی تعلیمات پر
شدت سے کار بند ہوتا ہے اس کے لیے دو اجر ہیں.عن ابن عمر قال قال رسول الله ﷺ مثل القرآن مثلاً الابل المعلقة ان
تعاهد صاحبها بعقلها امسكها عليه و ان اطلق عقلها ذهبت
(ابن ماجه کتاب الادب باب ثواب القرآن)
یعنی قرآن کی مثال بندھے ہوئے اونٹ کی مانند ہے.جب تک اس کا مالک اس کی رہی
تھامے رکھے گا وہ اس کے پاس رہے گا اور اگر چھوڑ دے گا تو وہ چلا جائے گا.اور اس میں شبہ نہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کو خدا تعالیٰ نے ایسے عشاق جانثار عطا کیے تھے جو
رضائے الہی کو رضائے رسول سے وابستہ سمجھتے اور آنحضور کی اطاعت کو دُنیا جہان کی فلاح اور کامیابی اور نجات کا
سامان سمجھتے تھے اس لیے آپ کے فرمودات اور ارشادات پر لبیک کہتے ہوئے پر کثرت کے ساتھ صحابہ نے
قرآن کریم حفظ کرنا شروع کر دیا.ابتدائی مؤمنین کا قرآن کریم سے عشق و محبت کا یہ حال تھا کہ ان میں سے ایسے لوگ بھی حفظ کرنے لگے جن
Page 51
عہد نبوی میں جمع و تدوین قرآن
35
کی علمی حالت ایسی نہ تھی کہ قرآنی مضامین کی گہرائی میں جا کر ان کو سمجھ پاتے.باوجود معنے نہ جاننے کے مسلمانوں
کا قرآن کریم کو یاد کرتے چلے جانا یقیناً محافظت قرآن کے الہی وعدہ کے پورا ہونے کی دلیل ہے.چنانچہ
روایت ہے:
عن عبد الله بن عمرو قال جاء رجل الى رسول الله ﷺ فقال يا رسول
الله اني اقرأ القرآن فلا اجد قلبي يعقل عليه
(مسند احمد؛ مسند المكثرين من الصحابه؛ مسند عبد الله بن عمرو بن العاص)
یعنی عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنھما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے پاس
ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ میں قرآن کریم تو پڑھتا ہوں مگر مجھے اس کی سمجھ نہیں آرہی ہوتی.حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب خلیفہ امسیح الثانی المصلح الموعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:
یہ اعتراض بھی کیا جاتا ہے قرآن کریم کے پیرو قرآن کریم کو بے معنی ہی پڑھتے رہتے
ہیں اس کے معنی سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے.لیکن اگر غور کیا جائے تو یہ بھی اس آیت (انا)
نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحفِظُونَ.الحجر :10) میں مذکور وعدہ کی تصدیق ہے.مسلمانوں
کے دل میں اللہ تعالیٰ نے کس طرح قرآن کریم کی محبت ڈال دی ہے کہ معنی آئیں یا نہ آئیں وہ
اسے پڑھتے چلے جاتے ہیں یقیناً ہر مسلمان کا فرض ہے کہ قرآن کریم کو با معنی پڑھے اور اس
طرف سے تغافل بڑی تباہی کا موجب ہوا ہے.( تفسیر کبیر جلد 4 صفحہ 18 کالم 2 زیر تفسیر سورۃ الحجر (10)
پھر آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر عمل کرتے ہوئے صحابہ بھی قرآن کریم کی درس و تدریس اور اسکی
تعلیمات کی اشاعت کے لیے کوشاں رہتے حضرت ابوسعید ابونضر کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں:
احفظوا عنا كما حفظنا عن رسول الله ﷺ
(مقدمه) سنن الدارمی باب من لم ير كتابة الحديث)
یعنی ہمارے زیر نگرانی اسی طرح قرآن شریف حفظ کر لو جس طرح ہم نے رسول کریم صلی
اللہ علیہ والہ وسلم کی نگرانی میں حفظ کیا تھا.اس روایت سے اس حقیقت پر بھی روشنی پڑی کی قرآن کریم ایک تواتر کے ساتھ حفظ کے ذریعہ رسول کریم
صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک حفاظ کے سینوں میں محفوظ چلا آرہا ہے اور حفظ قرآن کی مبارک عادت
امت محمدیہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے دور سے لے کر بغیر کسی وقفہ کے اب تک جاری ہے.ساری
Page 52
الذكر المحفوظ
36
دُنیا میں مسلمانوں کی بستیوں میں حافظ قرآن موجود ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی حیات مبارکہ
سے لے کر بلا شبہ اور بلا مبالغہ ہر دور میں ہزاروں ہزار حفاظ موجود رہے ہیں.حفظ قرآن کے بارہ میں امت مسلمہ کی ایک غیر معمولی عادت کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مرزا بشیر الدین محمود
احمد صاحب خلیفہ اسیح الثانی اصلح الموعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:
ایک ترکیب مسلمانوں نے حفاظت کی یہ اختیار کی ہوئی ہے اور اس پر صدیوں سے عمل
ہوتا چلا آیا ہے کہ جو پیدائشی نابینا ہوتے ہیں انہیں قرآن کریم حفظ کروا دیتے ہیں اور خیال کیا
جاتا ہے کہ نابینا کوئی دنیوی کام تو کر نہیں سکتا.کم سے کم وہ قرآن کی خدمت ہی کرے گا.یہ
رواج اتنا غالب ہے کہ لاکھوں مسلمان نابینوں کو بغیر پوچھے اور بغیر دریافت کیے ایک ہندوستانی
ملتے ہی حافظ صاحب کے نام سے یاد کر یگا یعنی وہ جس نے سارا قرآن یاد کیا ہوا ہے.اس کی
وجہ یہ ہے کہ نا بینوں میں سے اتنے حافظ قرآن ہوتے ہیں کہ عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ
ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی نابینا ہو اور قرآن کا حافظ نہ ہو.“
مزید فرماتے ہیں:
(دیباچہ تفسیر القرآن ضیاء الاسلام پر یس ربوہ صفحہ 277)
ہر رمضان میں ساری دنیا کی ہر بڑی مسجد میں سارا قرآن کریم حافظ لوگ حفظ سے بلند آواز
کے ساتھ ختم کرتے ہیں ایک حافظ امامت کراتا ہے اور دوسرا حافظ اس کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے تا اگر
کسی جگہ پر وہ بھول جائے تو اُسکو یاد کرائے.اس طرح ( اس ایک ماہ میں ہی ) ساری دنیا میں
لاکھوں جگہ پر قرآن کریم صرف حافظہ سے دہرایا جاتا ہے.یہی وہ باتیں ہیں جن کی وجہ سے یورپ
کے دشمنوں کو بھی تسلیم کرنا پڑا ہے کہ قرآن کریم رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے لیکر آج تک
محفوظ چلا آتا ہے اور یہ کہ یقینی طور پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ جس شکل میں قرآن کریم محمد صلی اللہ علیہ والہ
وسلم نے دنیا کو دیا تھا اُسی شکل میں آج موجود ہے.(دیباچہ تفسیر القرآن ضیاء الاسلام پر لیس ربوہ صفحہ 277)
پس رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے لے کر آج تک ہر دور میں ہزاروں ہزار ایسے حفاظ ہر وقت موجود
رہے ہیں جو قرآن کریم کو مکمل طور پر زبانی یا در کھتے ہیں اور سناتے رہتے ہیں اور اپنی نگرانی میں مزید حفاظ تیار کرتے
چلے جاتے ہیں.ان حفاظ کی تعداد کسی دور میں بھی پہلے سے کم نہیں ہوئی بلکہ ہمیشہ بڑھی ہے.یہ سلسلہ رسول کریم
صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے لے کر اب تک جاری ہے.
Page 53
عہد نبوی میں جمع و تدوین قرآن
37
اَلْفَضْلُ مَا شَهِدَتْ بِهِ الْأَعْدَاءُ
Dr.Maurice Bucaille مذہبی لحاظ سے عیسائی، ایک فرانسیسی سرجن ، اور مذہب اور سائنس کی دُنیا کی ایک
نامور شخصیت ہیں.حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں غرق ہونے والے فرعون "Meneptah" پر آپ کو
تحقیق کے لیے چنا گیا.آپ اپنی مشہور کتاب "The Bible The Quran and Science"میں لکھتے ہیں:
It (Quranic Revelation) spanned a period of some
twenty years and, as soon as it was transmitted to
Muhammad by Archangel Gabriel, believers learned it by
heart.It was also written down during Muhammad`s life.(The bible The Quran and Science (translation from French by
Alastair D.Pannel and The Ahthor)Under Heading Conclusions
Pg 250-251)
یعنی قرآنی وحی کا دورانیہ لگ بھگ 20 سال پر محیط ہے.جو نہی یہ ( وحی ) جبرائیل کے ذریعہ
) تک پہنچائی جاتی ، مومنین فوراً اسے حفظ کر لیتے.یہ محمد (ﷺ) کی زندگی میں ہی
لکھ بھی لی گئی تھی.قرآن کریم کے حفظ کے غیر معمولی تو اتر کے بارہ میں ممتاز مستشرق Kenneth Cragg رقم طراز ہیں:...this phenomenon of Qur'anic recital means that the
text has traversed the centuries in an unbroken living
sequence of devotion.It cannot, therefore, be handled as
an antiquarian thing, nor as a historical document out of
a distant past.The fact of hifz (Qur'anic memorization)
has made the Qur'an a present possession through all
the lapse of Muslim time and given it a human currency
in every generation, never allowing its relegation to a
bare authority for reference alone."
(Kenneth Cragg, The Mind of the Qur'an, London: George Allen
& Unwin, 1973, p.26)
قرآن کریم کے حفظ کا اعجاز یہ ہے کہ متن قرآنِ کریم صدیوں کا سفر طے کرتے ہوئے
انتہائی محبت اور خلوص اور وقف کی روح کے ساتھ ایک تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے.لہذا اس
کے ساتھ نہ تو کسی قدیم چیز جیسا سلوک روا رکھنا چاہیے اور نہ ہی اسے محض تاریخی دستاویز سمجھنا
درست ہے.در حقیقت حفظ کی خوبی نے اس کتاب کو مسلم تاریخ کے مختلف ادوار میں زندہ و
جاوید رکھا ہے اور بنی نوع کے ہاتھ میں نسلاً بعد نسل ایک معتبر متاع تھما دی اور کبھی بھی محض
غیرا ہم کتابی صورت میں نہیں چھوڑا.
Page 54
الذكر المحفوظ
وہیلئم گرا ہم لکھتے ہیں:
38
The Qur'an is perhaps the only book, religious or
secular, that has been memorized completely by millions
of people.(William Graham, Beyond the Written Word, UK: Cambridge
University Press, 1993, p.80)
یعنی قرآن کریم مذہبی اور غیر مذہبی کتابوں میں شائد واحد کتاب ہے جو کہ لاکھوں لاکھ
لوگوں کے ذریعے مکمل طور پر حفظ کی جاتی رہی.مشہور مستشرق اور رومن کیتھولک نن کیرم آرمسٹرانگ لکھتی ہیں :
جب بھی کوئی آیت پیغمبر اسلام پر نازل ہوتی ، آپ اسے بلند آواز میں صحابہ کرام کو سناتے
جوا سے یاد کر لیتے اور جولکھنا جانتے تھے، اسے لکھ لیتے.محمد باب دوم، صفحہ 61 پبلشرز بعلی پلاز 30 مزنگ روڈ لا ہور )
اور بھی بہت سے نامی گرامی مستشرق ایسے ہیں جو بعد تحقیق اس امر کی گواہی دیتے ہیں کہ قرآن کریم محمد صلی
اللہ علیہ والہ وسلم کی زندگی میں ہی تحریری صورت میں اور حفظ کے ذریعہ محفوظ کیا جاچکا تھا اور آج بھی بعینہ محفوظ
ہے جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا.مختصر یہ کہ قرآن کریم مذہبی کتب میں واحد کتاب ہے جو کہ نزول کے ساتھ ساتھ صاحب وحی کے زیر نگرانی
ایک سے زیادہ نسخوں میں تحریری شکل میں محفوظ ہورہی تھی.واحد مذہبی کتاب ہے جو کہ نزول کے ساتھ ساتھ
صاحب وحی کے زیر نگرانی حفظ ہوری تھی اور آج تک اس تواتر کے ساتھ لکھی اور حفظ کی جاتی ہے.حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب خلیفہ اسیح الثانی اصلح الموعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:
آج اگر بائبل کے سارے نسخے جلا دیے جائیں تو بائبل کے پیرو اس کا بیسواں حصہ بھی
دوبارہ جمع نہیں کر سکتے.لیکن قرآن مجید کو یہ فخر حاصل ہے کہ اگر سارے نسخے قرآن مجید کے دنیا
سے مفقود کر دیے جائیں.تب بھی دو تین دن کے اندر مکمل قرآن مجید موجود ہوسکتا ہے اور
بڑے شہر تو الگ رہے.ہم قادیان جیسی چھوٹی بستی میں ایسے فوراً حرف بحرف لکھوا سکتے ہیں.( تفسیر کبیر جلد 4 صفحہ 18 کالم 2 زیر تفسیر سورة الحجر: 10)
تلاوت قرآن کریم
پھر قرآن کریم کی حفاظت کا ایک ذریعہ کثرت سے اس کی تلاوت کرنا بھی ہے.حضرت رسول کریم صلی اللہ
علیہ والہ وسلم تلاوت قرآن پر بھی بہت زور دیتے اور کثرت سے تلاوت کرنے کی تاکید فرماتے.چنانچہ اس
نصیحت پر امت آج بھی پوری طرح کار بند ہے.حفاظت کے ضمن میں کثرت تلاوت بہت اہم کردار ادا کرتی
Page 55
عہد نبوی میں جمع و تدوین قرآن
39.ہے.کثرت سے تلاوت کرنے والا حافظ نہ سہی مگر ایک نیم حافظ ضرور بن جاتا ہے اور قرآن کریم کے متن سے
اسقدر مانوس ہو جاتا ہے جب اس کے سامنے تلاوت کی جائے تو غلطی کی صورت میں فوراً درستی کرا دیتا ہے.گو
زبانی اسے مکمل قرآن
نہ بھی یاد ہو، وہ چھوٹی سی غلطی پر بھی فوراً مطلع ہو جاتا ہے اور اصلاح کروا دیتا ہے.تلاوت
کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ امت کے دلوں میں اس کی اہمیت جاگزین کرنے کا بیڑا بھی اللہ
تعالیٰ خود اُٹھاتا ہے.کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی طاقت میں تھا ہی نہیں کہ دلوں میں اتنی محبت پیدا
کر دیں جو آئندہ زمانوں پر بھی محیط ہو اور کسی دور میں بھی امت کلام اللہ کی تلاوت کے فریضہ سے غافل نہ ہو.بہت بھی ہوتا تو یہی کہ آپ کی خوشنودی کی خاطر لوگ آپ کے سامنے تو تلاوت کرلیا کرتے مگر جب آپ سامنے
نہ ہوتے یا جب آپ کی وفات ہو جاتی تو پھر یہ سلسلہ ختم ہو جاتا.مگر خدا تعالیٰ نے تلاوت قرآن کو زندہ رکھنا اپنی
ذمہ داری قرار دیا.اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے:
إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَ قُرْآنَهُ (القيامة :18)
یعنی اس قرآن کا جمع کرنا اور اس کی تلاوت ہماری ذمہ داری ہے.اس آیت سے تلاوت کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جمع قرآن کے ساتھ اس کو رکھا ہے.قرآن کریم با قاعدہ تلاوت کے آداب سکھاتا ہے.مثلاً یہ کہ تلاوت کرنے سے قبل ظاہری اور باطنی پاکیزگی شرط
ہے.فرمایا:
لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُون (الواقعة : 80)
ترجمہ: کوئی اسے چھو نہیں سکتا سوائے پاک کیے ہوئے لوگوں کے.پھر یہ کہ تلاوت سے قبل خدا تعالیٰ سے شیطانی وساوس سے بچنے کی دعا کر لیا کرو:
فَإِذَاقَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّحِيمِ (النحل: 99)
ترجمہ: پس جب تو قرآن پڑھے تو دھتکارے ہوئے شیطان سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کر
حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی معہود علیہ السلام استعاذہ کی حکمت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:
اعلم يا طالب العرفان انه من احل نفسه محل تلاوة الفاتحة و الفرقان
فعليه ان يستعيذ من الشيطن كما جاء في القرآن فان الشيطن
قـديـدخـل حمـى الحضرة كالسارقين و يـدخــل الـحـرم العاصم
للمعصومين - فاراد الله ان ينجى عباده من صول الخناس عند قراءة
الفاتحة وكلام رب الناس ويد فعه بحربته منه و يضع الفاس في الراس
Page 56
40
الذكر المحفوظ
و يخلـص الـغـافـلـيـن مـن الـنـعـاس فـعلم كلمته منه لطرد الشيطان
المدحور الى يوم النشور ( اعجاز المسیح روحانی خزائن جلد 18 صفحه 81-82)
ترجمہ: اے طالب معرفت جان لے کہ جب کوئی شخص سورۃ فاتحہ اور قرآن کریم کی تلاوت
کرنے لگے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اعوذ باللہ من الشیطان پڑھے جیسا کہ قرآن کریم میں
حکم ہے.کیونکہ کبھی شیطان خدا تعالیٰ کی رکھ میں چوروں کی طرح داخل ہو جاتا ہے اور اس حرم
کے اندر آ جاتا ہے جو معصومین کا محافظ ہے.پس اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ وہ سورت فاتحہ اور
قرآن مجید کی تلاوت کے وقت اپنے بندوں کو شیطان کے حملہ سے بچائے ، اسے اپنے حربہ سے
پسپا کرے، اس کے سر پر تبر رکھے اور غافلوں کو غفلت سے نجات دے.پس اس نے شیطان کو
دھتکارنے کے لیے جو قیامت تک راندہ درگاہ ہے اپنے ہاں سے بندوں کو ایک بات سکھائی.پھر یہ ادب سکھلایا کہ جب تلاوت کی جارہی ہو تو خاموشی سے سنی جائے.وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ اَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (الاعراف: 205)
ترجمہ: اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہوتا کہ تم پر رحم کیا جائے.قرآن کریم کی ان تعلیمات کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کوغور سے تلاوت سننے کی بھی بہت
تاکید فرماتے تھے.روایت ہے:
اِنَّ الَّذِى يَقْرَأُ الْقُرْآنَ لَهُ أَجْرٌ وَإِنَّ الَّذِي يَسْتَمِعُ لَهُ أَجْرَانِ
(الدارمي ؛ فضائل القرآن؛ فضل من استمع الى القرآن)
جو قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اس کے لیے ایک اجر ہے اور جو غور سے سُنتا ہے اس کے
66
لیے دہرا اجر ہے
آداب تلاوت کے ضمن میں یہاں تک راہنمائی فرمائی کہ ایسے مبارک اوقات بھی بتا دیے کہ دن اور رات کی
کن گھڑیوں میں تلاوت قرآن کریم اللہ تعالیٰ کے حضور زیادہ پسندیدہ ہے.ان میں سے ایک وقت فجر کا ہے
جب کہ انسانی ذہن مکمل طور پر پرسکون ، تازہ دم اور ہشاش بشاش ہوتا ہے.چنانچہ فرمایا:
أقِمِ الصَّلوة لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ الَّيْلِ وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ طَ إِنَّ قُرْآنَ
الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا(بني السرائيل:79)
ترجمہ: سورج کے ڈھلنے سے شروع ہو کر رات کے چھا جانے تک نماز کو قائم کر اور فجر کی
تلاوت کو اہمیت دے.یقیناً فجر کو قرآن پڑھنا ایسا ہے کہ اُس کی گواہی دی جاتی ہے.
Page 57
عہد نبوی میں جمع و تدوین قرآن
41
ذیل میں بطور نمونہ چند ایک احادیث درج کی جاتی ہیں جن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے تلاوت
کی اہمیت ، آداب تلاوت اور فضائلِ تلاوت کا ذکر فرمایا ہے.عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى قَالَ سَمِعْتُ مَحَمَّدَ بْنَ كَعْبِ الْقُرَظِي قَالَ سَمِعْتُ
عَبْدِ اللهِ بن مَسْعُودٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ
ﷺ: مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِّنْ كِتَابِ
اللَّهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا لَا أَقُولُ الَّمٌ حَرْفٌ وَلَكِنْ أَلِفٌ
حرُفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ -
(بخاری کتاب فضائل القرآن باب ما جاء فيمن قرا حرفا من القرآن...)
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا:
" جس نے قرآن کا ایک حرف بھی پڑھا اس کو اس کے پڑھنے کی وجہ سے ایک نیکی ملے گی
اور اس ایک نیکی سے دس اور نیکیاں ملیں گی.میں نہیں کہتا کہ الم ایک حرف ہے بلکہ الف ایک
حرف ہے لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے.“
اسی ارشاد کی تعمیل میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے اپنی زندگی کا شغل ہی قرآن کریم پڑھنا پڑھانا بنالیا تھا.أَبُو أُمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: اقْرَءُ وا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ
يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِاَصْحَابِهِ - َاقْرَءُ ُوا الزَّهْرَاوَيْنِ : الْبَقَرَةَ وَسُورَةَ آلِ
عِمْرَانَ - فَإِنَّهُمَا يَأْتِيَان يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ أَوْ كَأَنَّهُمَا غَايَتَانِ
أَوْكَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرِ صَوَافَ - تُحَاجَّانِ عَنْ أَصْحَابِهِمَا إِقَرَثُوْا سُوْرَةَ
الْبَقَرَةِ فَإِنَّ أَخُذَهَا بَرَكَةٌ وَتَرَكَهَا حَسْرَةٌ وَلَا يَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ -
(مسلم کتاب صلاة المسافرين باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة)
حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم
کو یہ فرماتے ہوئے سنا: قرآن پڑھا کرو یہ قیامت کے روز اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا
زهراوين یعنی سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران پڑھا کرو یہ قیامت کے روز اس طرح آئیں گی گویا دو
بدلیاں ہوں یا ایسے کہ گویا صف آراء پرندوں کے دوغول ہوں جو اپنے پڑھنے والوں پر سایہ تیکن
ہوں گے.سورۃ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کو پڑھتے رہنا برکت کا موجب ہے اور اس کو ترک کر دینا
حسرت کا موجب ہوگا جھوٹے شعبدہ باز اس پر غالب نہیں آ سکتے.“
عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
ﷺ : الْجَاهِرُ بِالْقُرْآنِ
Page 58
الذكر المحفوظ
42
كَالْجَاهِرِ بِالصَّدَقَةِ وَالْمُسِرُّ بِالْقُرْآن كَالْمُسِرِّ بالصَّدَقَةِ -
(سنن ابی داود كتاب التطوع باب فى رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل)
عقبہ بن عامر جہنی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا:
اونچی آواز سے قرآن پڑھنے والا ایسا ہے جیسے لوگوں کے سامنے خیرات کرنے والا اور
66
آہستہ آواز سے قرآن پڑھنے والا ایسا ہے جیسے چپکے سے خیرات کرنے والا.“
عَنْ عُبَيْدَةَ الْمُلَيْكِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صلى الله عليه وسلم يَا أَهْلَ الْقُرْآن لَا تَتَوَسَّدُوا الْقُرْآنَ وَاتْلُوهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ
مِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَافْشُوهُ وَتَغَنُّوهُ وَتَدَبَّرُوْا مَا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
(رواه البيهقي في شعب الايمان بحواله مشكاة المصابيح كتاب فضائل القرآن)
حضرت عُبَيْدَه مُلکی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ اے اہل قرآن! قرآن پڑھے بغیر نہ سویا کرو اور اس کی تلاوت رات کو اور دن کے
وقت اس انداز میں کرو جیسے اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے اور اس کو پھیلاؤ اور اس کو خوش الحانی
سے پڑھا کرو اور اس کے مضامین پر غور کیا کرو تا کہ تم فلاح پاؤ.حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی معہود علیہ السلام فرماتے ہیں:
قرآن شریف کو بھی خوش الحانی سے پڑھنا چاہئے.بلکہ اس قدر تاکید ہے کہ جو شخص.قرآن شریف کو خوش الحانی سے نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے.اور خود اس میں ایک
اثر ہے.عمدہ تقریر خوش الحانی سے کی جائے تو اس کا بھی اثر ہوتا ہے.وہی تقریر ثر ولیدہ
زبانی سے کی جائے تو اس میں کوئی اثر نہیں ہوتا.جس شئے میں خدا تعالیٰ نے تاثیر رکھی
ہے اس کو اسلام کی طرف کھینچنے کا آلہ بنایا جائے تو اس میں کیا حرج ہے.ایک دوسری جگہ فرمایا :
( ملفوظات جلد چہارم صفحہ 524)
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش الحانی سے قرآن سنا تھا اور آپ اس پر روئے بھی
تھے.جب یہ آیت و جئنابك على هَؤُلَاءِ شهيدًا (النساء:42) آپ روئے اور فرمایا
بس کر میں آگے نہیں سن سکتا.آپ کو اپنے گواہ گذرنے پر خیال گذرا ہوگا.ہمیں خود خواہش
رہتی ہے کہ کوئی خوش الحان حافظ ہو تو قرآن سنیں.( ملفوظات جلد سوم صفحہ 161,162 )
Page 59
عہد نبوی میں جمع و تدوین قرآن
43
قرآن شریف تدبر و تفکر وغور سے پڑھنا چاہیے.حدیث شریف میں آیا ہے رُبَّ قاد
يَلْعَنُهُ الْقُرآن یعنی بہت ایسے قرآن کریم کے قاری ہوتے ہیں جن پر قرآن کریم لعنت بھیجتا
ہے.جو شخص قرآن پڑھتا اور اس پر عمل نہیں کرتا اس پر قرآن مجید لعنت بھیجتا ہے.تلاوت
کرتے وقت جب قرآن کریم کی آیت رحمت پر گذر ہو تو وہاں خدا تعالیٰ سے رحمت طلب کی
جاوے اور جہاں کسی قوم کے عذاب کا ذکر ہو تو وہاں خدا تعالیٰ کے عذاب سے خدا تعالیٰ کے
آگے پناہ کی درخواست کی جاوے اور تدبر و غور سے پڑھنا چاہیے اور اس پر عمل کیا جاوے.( ملفوظات جلد بحجم صفحہ 157 )
روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آنحضور خود کس انداز میں تلاوت کیا کرتے تھے.چنانچہ روایت ہے کہ:
عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسًا عَنْ قِرَاءَةِ النَّبِيِّ
ﷺ فَقَالَ : كَانَ يَمُدُّ مَدًّا.(سنن ابی داود کتاب الوتر باب استحباب الترتيل في القراءة)
حضرت قتادہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت انسؓ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قراءت
کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ نبی ﷺہ ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کیا کرتے تھے.عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْطَعُ قِرَاءَ تَهُ يَقُولُ:
اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - ثُمَّ يَقِفُ ثُمَّ يَقُولُ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم- ثُمَّ يَقِفُ
(رواه الترمذى بحواله مشكاة المصابيح كتاب فضائل القرآن حدیث نمبر ٢٢٠٥)
ام المومنین حضرت اُم سلمہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
قرآن کریم کی تلاوت ٹھہر ٹھہر کر کیا کرتے تھے آپ الحَمدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِین پڑھ
کر توقف فرماتے پھر الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ پڑھتے اور توقف فرماتے.عَنْ يَعْلَى بْنِ مَمْلَكٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ قِرَاءَةِ النَّبِيِّ
صلى الله عليه وسلم فَإِذَا هِيَ تَنْعُتُ قِرَاءَةٌ مُفَسِّرَةً حَرْفًا حَرْفًا.(رواه الترمذى وابو داود والنسائى بحواله مشكاة المصابيح كتاب فضائل القرآن
يعلى بِنُ مَمُلِكُ روایت کرتے ہیں کہ میں نے اُم المومنین حضرت اُم سلمہ رضی اللہ عنہا
سے آنحضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے قرآن کی تلاوت کے بارہ میں دریافت کیا تو انہوں نے
کہا کہ آنحضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی قراءت ، قراءت مفسرہ ہوتی تھی یعنی ایک ایک حرف کے
پڑھنے کی سننے والے کو سمجھ آ رہی ہوتی تھی.عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: زَيْنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ -
(سنن ابی داود کتاب الوتر باب استحباب الترتيل في القراءة)
Page 60
الذكر المحفوظ
44
حضرت براء بن عازب سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا کہ
قرآن کو اپنی آوازوں سے زینت دو.پھر یہ بھی احادیث ملتی ہیں کہ قرآن کریم کے حکم کی تعمیل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم بہت تاکید کرتے
تھے کہ تلاوت توجہ سے سنی جائے.حضرت امام بخاری نے اپنی صحیح میں کتاب فضائل القرآن میں قرآن کریم غور
سے سننے کے بارہ میں آنحضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی نصائح اور اسوہ کے بارہ میں روایات کا ایک باب باندھا
ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ضمن میں کس قدر تاکید فرماتے تھے اور صرف صحیح
بخاری ہی نہیں بلکہ قریباً تمام کتب حدیث میں ملتے جلتے مضامین کی احادیث کثرت سے ملتی ہیں.آنحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی ان نصائح پر صحابہ نے اپنی فطری اطاعت کی عادت کے مطابق والہانہ
لبیک کہا.تعلیم القرآن کے موضوع کے تحت اس بارہ میں روایات درج کی جا چکی ہیں کہ کس طرح بہت سے
صحابہ نے قرآن کریم کی تعلیم و تدریس کو ہی اپنا شغل بنالیا اور دن رات اس کی تلاوت میں مشغول رہتے تھے.اللہ تعالیٰ صحابہ کے حق میں گواہی دیتے ہوئے فرماتا ہے:
الَّذِينَ آتَيْنَهُمُ الْكِتَبَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَ مَنْ يَكْفُرُ بِهِ
فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَسِرُونَ (البقرة:122)
وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس کی ویسی ہی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی
تلاوت کا حق ہے.یہی وہ لوگ ہیں جو ( در حقیقت ) اس پر ایمان لاتے ہیں.اور جو کوئی بھی
اس کا انکار کرے پس وہی ہیں جو گھاٹا پانے والے ہیں
چنانچہ روایات میں ہے کہ : حضرت
عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنھما سے آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کتنی
دیر میں قرآن کریم کا مکمل دور کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کی کہ ایک رات میں.آپ نے فرمایا:
اقرا الْقُرْآنَ فِي شَهْرٍ قُلْتُ إِنِّى أَجِدُ قُوَّةً قَالَ فَاقْرَأَهُ فِي سَبْعِ وَلَا تَزِدْ عَلَى
ذَالِكَ
(بخاری کتاب فضائل القرآن باب في كم يقرا القرآن)
ایک مہینہ میں قرآن
کریم کا دور مکمل کیا کرومیں نے عرض کی کہ مجھے اس سے زیادہ کی تو فیق
ہے.آپ نے فرمایا کہ پھر ایک ہفتہ میں مکمل کر لیا کرو لیکن اس سے جلدی نہیں.اس روایت سے ایک تو یہ علم ہوتا ہے کہ صحابہ کو قرآن کریم سے کس درجہ عشق تھا اور وہ کس طرح دن رات اس
کی تلاوت کرنا چاہتے تھے.دوسری جانب حفاظت قرآن کے حوالہ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
Page 61
عہد نبوی میں جمع و تدوین قرآن
45
علیہ وسلم کس قدر گہری نظر سے حفاظت قرآن کا اہتمام فرماتے.اس طرح تیزی سے پڑھنے سے معانی کی طرف
بہت کم توجہ ہوتی ہے.اس لیے اس طرح تلاوت کرنی چاہیے کہ معانی بھی سمجھ آرہے ہوں.حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود علیہ السلام آداب تلاوت کے ضمن میں نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں:
لوگ قرآن شریف پڑھتے ہیں مگر طوطے کی طرح یونہی بغیر سوچے سمجھے چلے جاتے ہیں.جیسے ایک پنڈت اپنی پوتھی کو اندھا دھند پڑھتا جاتا ہے.نہ خود سمجھتا ہے اور نہ سننے والوں کو پتہ
لگتا ہے.اسی طرح پر قرآن شریف کی تلاوت کا طریق صرف یہ رہ گیا ہے کہ دو چار سپارے
پڑھ لئے اور کچھ معلوم نہیں کہ کیا پڑھا.زیادہ سے زیادہ یہ کہ سر لگا کر پڑھ لیا اور ق اور ع کو
پورے طور پر ادا کر دیا.قرآن شریف کو عمدہ طور پر اور خوش الحانی سے پڑھنا بھی ایک اچھی
بات ہے.مگر قرآن شریف کی تلاوت کی اصل غرض تو یہ ہے کہ اس کے حقائق اور معارف پر
اطلاع ملے اور انسان ایک تبدیلی اپنے اندر پیدا کرے.( ملفوظات جلد اول صفحہ 284 285)
اسی طرح تلاوت قرآن کریم کا ایک اور ادب یہ سکھلایا :
اللہ تعالیٰ قرآن شریف کی تعریف میں فرماتا ہے.هُدى لِلْمُتَّقِين (البقره:3) قرآن بھی
ان لوگوں کے لئے ہدایت کا موجب ہوتا ہے جو تقویٰ اختیار کریں.ابتدا میں قرآن کے دیکھنے
والوں کا تقویٰ یہ ہے کہ جہالت اور حسد اور بخل سے قرآن شریف کو نہ دیکھیں بلکہ نور قلب کا
تقوی ساتھ لے کر صدق نیت سے قرآن شریف کو پڑھیں.( ملفوظات جلد اول صفحہ 536)
اسلامی عبادات کے ساتھ خصوصی طور پر قرآن کریم کی تلاوت کو بہت مضبوطی سے باندھ دیا گیا ہے.نماز دس
برس کی عمر سے ہر مسلمان پر دن میں پانچ مرتبہ پڑھنا فرض ہے اور ہر نماز میں قرآن کریم کا کچھ حصہ پڑھنا
ضروری ہے.اس لیے ہر مسلمان کو قرآن کریم کا کچھ نہ کچھ حصہ یاد کرنا ہی پڑتا ہے اور امام کی تلاوت پیچھے صفوں
میں کھڑے نمازی غور سے سنتے اور کسی بھی غلطی کی صورت میں اصلاح کرواتے ہیں.نیز اس طرح بار بار تلاوت
اور بار بار سننے سے مختلف لوگوں کو قرآن کریم کے مختلف حصے از بر ہو جاتے ہیں.آنحضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم نمازوں میں قرآن کریم کی لمبی تلاوت فرمایا کرتے تھے.چنانچہ ایک روایت
ملتی ہے کہ ایک دفعہ آپ نے نماز تہجد میں قرآن شریف کی پہلی پانچ سورتوں کی بالترتیب تلاوت فرمائی جو مجموعی
طور پر قرآن کریم کے پانچویں حصہ کے برابر ہیں.(ابو داؤد کتاب الصلوة باب ما يقول الرجل
فی رکوعه) اسی طرح بخاری میں ذکر ملتا ہے کہ لمبے لمبے قیام کرنے کی وجہ سے آپ کے پاؤں متورم
Page 62
الذكر المحفوظ
46
ہو جایا کرتے تھے.(بخاری کتاب الصلاة باب قيام النبي ﷺ ان ترم قدماه.....)
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ فِي الصَّلَاةِ
أَفْضَلُ مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ
أَفْضَلُ مِنَ التَّسْبِيحَ وَالتَّكْبِيرِ
(مشكاة المصابيح كتاب فضائل القرآن الفصل الثالث)
ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے
فرمایا، نماز میں قرآن کریم کا پڑھنا افضل ہے اس پڑھنے سے جو نماز کے علاوہ پڑھا گیا ہو اور نماز
کے علاوہ قرآن کریم پڑھنا خدا تعالیٰ کی پاکیزگی اور بڑائی بیان کرنے سے زیادہ افضل ہے.اسی طرح سال میں ایک مرتبہ ایک رمضان المبارک میں قرآن کریم کا کم از کم ایک دور کرنے کی عادت
بہت مبارک ہے جو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی سنت کی اتباع میں آپ کے زمانہ سے چلی آرہی
ہے، اس کے علاوہ نفل نماز میں قرآن کریم کا ایک دور ہے.یہ مبارک عادت حضرت عمر کے دور سے نماز تراویح کی
شکل میں باقاعدہ جاری ہے.حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب خلیفہ المسیح الثانی المصلح الموعود رضی اللہ عنہ
فرماتے ہیں:
ہر رمضان میں ساری دنیا کی ہر بڑی مسجد میں سارا قرآن کریم حافظ لوگ حفظ سے بلند آواز
کے ساتھ ختم کرتے ہیں ایک حافظ امامت کراتا ہے اور دوسرا حافظ اس کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے تا
اگر کسی جگہ پر وہ بھول جائے تو اُس کو یاد کرائے.اس طرح ( اس ایک ماہ میں ہی ) ساری دنیا
میں لاکھوں جگہ پر قرآن کریم صرف حافظہ سے دہرایا جاتا ہے.(دیباچہ تفسیر القرآن ضیاء الاسلام پر یس ربوہ صفحہ 277)
امت مسلمہ نے صرف تلاوت کی کثرت کی حد تک ہی لبیک نہیں کہا بلکہ کمال اطاعت کا ایک بے مثل نمونہ
اس طرح بھی قائم کیا کہ تلاوت قرآن کو با قاعدہ ایک سائنس کی شکل دی.حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم
کی ہدایات اور آپ کے ارشادات کی روشنی میں ، قرآن کریم کی تلاوت کے ضمن بھی امت مسلمہ نے بہت سے
نئے علوم کی بنیاد ڈالی.کسی اور زبان میں دیکھ کر پڑھنے کے بارہ میں ایسی تحقیق اور تفصیل سے اصول وضع نہیں
کیے گئے جیسا کہ قرآن کی خدمت کی خاطر امت مسلمہ میں عربی زبان میں وضع کیے گئے.مسلمانوں میں کس
کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے اور تلاوت کرنے کے آداب اور علوم کو کس درجہ اہمیت حاصل ہے
اس کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ ترتیل اور تجوید کا فن جو کہ تلاوت قرآن کے آداب وقواعد اور انداز کے بارہ
میں با قاعدہ ایک سائنس کی شکل اختیار کر چکا ہے اور دُنیا بھر کے مسلمانوں میں بہت مقبول اور اس کا سیکھنا
Page 63
47
عہد نبوی میں جمع و تدوین قرآن
و
باعث عزت و تکریم سمجھا جاتا ہے.آج ساری دُنیا میں بڑی مساجد میں نماز تراویح میں اُن قراء کا اہتمام کیا جاتا
ہے جوفن تجوید کے اصولوں سے واقف ہوں اور تلاوت کے آداب جانتے ہوں.ساری دُنیا میں حسن قراءت کے
مقابلہ جات منعقد ہوتے ہیں نیز تمام بڑی مجالس کا آغاز صحت تلفظ اور آداب فن تجوید کے ساتھ تلاوت قرآن
کریم سے کیا جاتا ہے.رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے دور سے ہی قرآن کریم دُنیا کی تمام کتب میں سب سے
زیادہ زبانی اور دیکھ کر پڑھی جانے والی کتاب ہے.آج تک دنیا کی کسی کتاب کے بارہ میں ایسے قوانین اور سائنس کی
بنیاد بھی نہیں ڈالی گئی جیسا کہ قرآن کریم کے صرف پڑھنے اور تلاوت کرنے کے لیے صدیوں سے رائج ہیں.مشہور مستشرق فلپ کے حتی لکھتے ہیں:
دنیا میں نصرانیوں کی تعداد مسلمانوں سے قریباً دوگنی ہے.لیکن اس کے باوجود وثوق سے کہا
جاسکتا ہے کہ دُنیا کی تمام کتابوں کے مقابلے میں صرف قرآن ہی سب سے زیادہ پڑھی جانے
والی کتاب ہے.اس کی وجہ یہ ہے کہ عبادتوں میں استعمال ہونے کے سوا یہ ایک ایسی کتاب بھی
ہے جس کے ذریعہ ہر نو جوان مسلمان عربی سیکھتا ہے.تاریخ عرب از فلپ کے حتی، ناشر : آصف جاوید برائے نگارشات ، باب 5 صفحہ 35 )
رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم اور صحابہ کا حفاظت قرآن کے ضمن میں بہت واضح اور حساس طرز عمل تھا کہ
مسلمان کسی بھی قیمت پر قرآن کریم کی حفاظت کے خیال سے غافل نہیں ہوتے تھے.گزشتہ سطور میں ہم نے
دیکھا ہے کہ کس درجہ احتیاط سے رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے جمع و تدوین قرآن کی ذمہ داری پورے
صدق وصفا اور دیانت داری کے ساتھ حفاظت کے تمام ظاہری تقاضے پورے کرتے ہوئے نبھائی اور ساتھ ساتھ
ہر لحاظ سے اس کی اشاعت بھی فرمائی.قرآن کریم کی عام تلاوت سے لے کر اس کے گہرے مضامین تک کی
تعلیم و تدریس کا فریضہ خود بھی ادا کرتے رہے اور صحابہ کو بھی نا صرف تاکید فرماتے رہے بلکہ بھر پور نگرانی فرماتے
ہوئے حفاظت کے تمام ممکنہ دُنیاوی تقاضے پورے کیے.آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کو وحی الہی کی حفاظت کا کس
قدر خیال تھا اور آپ اس ذمہ داری کا کتنا احساس کرتے تھے اسکا اندازہ قرآن کریم کی اس گواہی سے ہوتا ہے کہ
آپ نزول کے وقت وحی الہی کو نزول کے ساتھ ساتھ دہراتے تھے.چنانچہ اللہ تعالیٰ آپ کو تسلی دی کہ اس قدر
بوجھ لینے کی ضرورت نہیں.اس کلام کی حفاظت اور اشاعت کا خدا تعالیٰ خود ذمہ دار ہے.پھر جونہی وحی کا نزول
ختم ہوتا اسے لکھوا لیتے لکھوا کر سُنتے اور تسلی کے بعد اشاعت کی اجازت دیتے.خود تعلیم و تدریس کا فریضہ انجام
دیتے اور بار بار حفاظ صحابہ سے سنتے.حجتہ الوداع کے موقع پر ساری امت کو گواہ بنایا کہ آپ نے پیغام الہی کو ان
تک مکمل صورت میں پہنچا دیا ہے اور اس الہی امانت کو کمال دیانت داری کے ساتھ حفاظت کے تمام ممکنہ تقاضے
پورے کرتے ہوئے بنی نوع کے سپر د کر دیا ہے.جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا اور آپ
کو بھی اور حضرت
Page 64
الذكر المحفوظ
48
ابوبکر" کو بھی اس کا علم ہو گیا تو اس درجہ احساس ذمہ داری اور اہتمام سے حفاظت قرآن کی خدمت سرانجام دینے
کے بعد اب آپ مکمل طور پر مطمئن تھے کہ قرآن کریم محفوظ ہو چکا ہے.حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو جب آپ
نے اپنے وصال کے قرب کی خبردی (بخاری کتاب المغازی باب مرض النبي ووفاته ) تو اس کے بعد آپ
قریباً چھ ماہ اور زندہ رہے ہیں.اگر ایک ذرہ بھی خیال ہوتا کہ ابھی کوئی کسر رہ گئی ہے تو ان چھ ماہ میں ہنگامی
بنیادوں پر آپ کو وہ کسر پوری کرنی تھی.مگر اس عرصہ میں آپ کے طرز عمل میں کوئی بے چینی یا فکر یا عملت دکھائی
نہیں دیتی.آپ مکمل طور پر مطمئن تھے کہ آپ نے اپنے سپر د اس ذمہ داری کو بہترین رنگ میں سرانجام دے دیا
ہے.ایک معمولی سوجھ بوجھ کے انسان کو اگر احساس ہو جائے کہ اس کا آخری وقت نزدیک ہے تو وہ اپنی زندگی
بھر کی کمائی کی حفاظت کے خیال سے اس کے بارہ میں وصیتیں کرواتا ہے.اسکی تقسیم کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے
اس کے بعد اس کی محنت ضائع نہ ہو جائے بلکہ درست ہاتھوں میں جائے.رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی
بے انتہا فہم وفراست سے بعید تھا کہ ابھی حفاظت قرآن کے ضمن میں کوئی کمی رہ گئی ہو اور آپ نے اُس کمی کو پورا
کرنے کا اہتمام نہ فرمایا ہو.ہاں ایک ذکر ملتا ہے کہ اپنے آخری ایام میں امت کے لیے آخری نصیحت کے طور پر
کچھ وصیت کرنے کے لیے آپ نے کاغذ قلم منگوایا.حضرت عمرؓ کے یہ کہنے پر کہ حسبنا کتاب اللہ “ (بخاری
كتاب الـمـغـازی بـاب مــرض النبی و وفاته ( یعنی ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، آپ نے اطمینان کا
اظہار فرما دیا.گویا یہی آخری وصیت تھی آپ کی.اب اگر کتاب اللہ کی حفاظت میں کوئی کسر رہ گئی تھی تو رسول کریم
اس موقع پر ضرور اس کی بھی نصیحت کرتے.پس جب قرآن کریم ایک ایسی واحد مذہبی کتاب ہے جو نزول کے ساتھ ساتھ ضبط تحریر میں لائی جاتی رہی
ہے.ہر دور میں تواتر کے ساتھ تحریری صورت میں موجود رہی ہے.پھر قرآن ہی وہ واحد مذہبی کتاب ہے جو کہ
مکمل طور پر حفظ کی جاتی ہے.ہر دور میں کثیر تعداد میں اس کے حفاظ موجود رہے ہیں.نمازوں میں پڑھی جاتی
ہے.دُنیا بھر میں سب کتابوں سے زیادہ دیکھی جاتی ہے اور سب کتابوں سے زیادہ اس کی تلاوت جاتی ہے ،تو
اس کی حفاظت میں کیا کسر رہ سکتی ہے؟ جس کتاب کی حفاظت کے لیے تحریر اور حفظ کے ساتھ ساتھ اتنے بہت
سے ذرائع بھی تمام تر دیانت داری کے ساتھ بروئے کار لائے جا رہے ہوں، اس کی حفاظت میں کس طرح
کوئی ادنی سا بھی شک ہوسکتا ہے؟
حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی معہود علیہ السلام فرماتے ہیں:
انصاف سے دیکھنا چاہیے کہ مسلمان جس پاک اور کامل کتاب پر ایمان لائے ہیں کس قدر
اس مقدس کتاب کو انہوں نے اپنے ضبط میں کر لیا ہے عموماً تمام مسلمان ایک حصہ کثیر قرآن
شریف کا حفظ رکھتے ہیں جس کو پنج وقت مساجد میں نماز کی حالت میں پڑھتے ہیں.ابھی بچہ
Page 65
49
عہد نبوی میں جمع و تدوین قرآن
پانچ یا چھ برس کا ہوا جو قرآن شریف اس کے آگے رکھا گیا.لاکھوں آدمی ایسے پاؤ گے جن کو
سارا قرآن شریف اول سے آخر تک حفظ ہے اگر ایک حرف بھی کسی جگہ سے پوچھو تو اگلی پچھلی
عبارتیں سب پڑھ کر سنادیں اور مردوں پر کیا موقوف ہے ہزاروں عورتیں سارا قرآن شریف
حفظ رکھتی ہیں.کسی شہر میں جا کر مساجد و مدارس اسلامیہ میں دیکھو صد ہالڑکوں اور لڑکیوں کو پاؤ
گے کہ قرآن شریف آگے رکھے ہیں اور با ترجمہ پڑھ رہے ہیں یا حفظ کر رہے ہیں اب سچ سچ
کہو کہ اس کے مقابل پر وید کا کیا حال ہے اور خود ایمانا اپنے ہی کانشنس سے پوچھ کر دیکھو کہ وید
کی حالت کو اس سے کیا نسبت ہے سو اس سے ہی تم سمجھ سکتے ہو کہ کس کتاب کے شامل حال
نصرت الہی ہے اور کونسی کتاب اپنی تعلیموں میں شہرت تام پا چکی ہے یوں تو منعصوں کا تعصب
خدا ہی مٹاوے تو مٹ سکتا ہے لیکن غور کرنے والی طبیعتیں سمجھ سکتی ہیں.شحنه حق روحانی خزائن جلد دوم صفحہ 333 ، 334 )
تعلیم القرآن
حفاظت قرآن کے ضمن میں امت محمدیہ میں قرآن کریم کی تعلیم رائج ہونے اور جاری وساری رہنے کا بھی
بہت اہم حصہ ہے.یہ ظاہر ہے کہ جس کتاب کے لفظ تو محفوظ ہوں لیکن معنوں کی حفاظت نہ ہو وہ محفوظ کتاب نہیں
کہلا سکتی.لیکن جس کتاب کی تعلیم ہر دور میں کسی قوم کے چھوٹے بڑے افراد میں عام ہو ممکن ہی نہیں کہ وہ کتاب
کسی بھی زمانہ میں ضائع ہو جائے.یہ بہت واضح امر ہے کہ جو تعلیم دلوں میں راسخ ہو جائے اور روزمرہ زندگی کا
حصہ بن جائے وہ مٹائی نہیں جاسکتی.چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جہاں قرآن کریم کی جمع کا ذمہ لیا وہاں اس
کی تعلیم اور
اس کے معانی کی تفہیم کا ذمہ بھی اپنے سر ہی لیا.قرآن کریم کی حفاظت کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کی راہنمائی کے
مطابق آنحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے جو مساعی فرما ئیں ان میں تعلیم القرآن کے حوالہ سے بہت اہم اور
بنیادی اقدامات کیے.چنانچہ آپ قرآن کریم کا علم حاصل کرتے رہنے کی بہت تاکید فرماتے تھے اور نہ صرف
علم حاصل کرنے کی تلقین فرماتے بلکہ صحابہ کو قرآن کریم سکھانے اور اسکی تعلیم کی اشاعت کی طرف توجہ دلاتے.سب سے پہلے معلم قرآن خود آپ تھے اور معلمین قرآن کے لیے اسوہ حسنہ بھی.چنانچہ آپ کی والہانہ اطاعت
کرنے والے جانثار صحابہ نے اس میدان میں بھی غیر معمولی اخلاص کے ساتھ بے نظیر نمونہ دکھایا.تاریخ کے اوراق
ان بے شمار مثالوں سے پُر ہیں کہ صحابہ کس شوق اور ولولہ سے اپنے آقا کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اور اس کی اس
خواہش کی تکمیل میں اور حفاظت قرآن کے باب میں اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اس میدان میں آگے آئے.سب سے پہلے تو قرآن کریم کی اندرونی گواہی موجود ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم سب سے پہلے
Page 66
الذكر المحفوظ
50
معلم القرآن تھے.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے.هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّنَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ آيَتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَبَ وَالْحِكْمَةَ - (الجمعة: 3)
یعنی وہی خدا ہے جس نے اُمی لوگوں میں انہی میں سے رسول بھیجا جو ان پر آیات کی
تلاوت کرتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور الکتاب کی تعلیم دیتا ہے اور اس کی حکمت سکھاتا ہے.چنانچہ کثرت سے روایات ملتی ہیں جن سے علم ہوتا ہے کہ آنحضور کس شوق اور تڑپ کے ساتھ صحابہ کو قرآن کریم
کی تعلیمات اور ان کی حکمت سے آگاہ کرتے اور تعلیم و تدریس کا فریضہ سر انجام دیا کیا کرتے تھے.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم القرآن کے سلسلہ میں نصائح اور اس راہ میں آپ کی عملی اور علمی سعی اور رہنمائی
کا مختصر بیان کرنے کے لیے نمونہ کے طور پر چند روایات درج کی جاتی ہیں.حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں:
كان رسول الله ﷺ يعلمنا القرآن
(مسند احمد بن حنبل جلد 2 مسند عبد الله بن عمر صفحه 157)
یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قرآن کریم کی تعلیم دیا کرتے تھے.کثرت سے ایسی روایات ملتی ہیں جن سے یہ گواہی ملتی ہے کہ بہت سے صحابہ نے آنحضور صلی اللہ علیہ والہ وس
سے قرآن کریم پڑھا تھا مثلاً حضرت عبداللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ:
والله لقد اخذت من فى رسول الله ﷺ بضعا و سبعين سورة
(بخاری کتاب فضائل القرآن باب القراء من اصحاب النبي.صله الله.خدا کی قسم میں نے آنحضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے منہ سے بہتر سے زائد سورتیں سیکھیں.اسی طرح ذکر ملتا ہے کہ :
ابی عمران سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے دور مبارک
میں جبکہ ابھی ہم کھیلنے کودنے کی عمر کے بچے تھے، آپ (ﷺ) ہمیں پہلے ابتدائی ایمان کی
باتیں سکھاتے پھر قرآن کریم کی تعلیم دیتے جس سے ہمارا ایمان پختہ ہوتا.(مقدمه سنن ابن ماجه باب فی الایمان)
حضرت عمر اور حضرت حکیم بن ہشام رضی اللہ عنہما کے واقعہ کا ذکر گزشتہ میں بھی ہو چکا ہے جس اس امر پر
روشنی پڑتی ہے کہ کس طرح صحابہ قرآن کریم کی حفاظت کے حوالے سے ایک دوسرے کی نگرانی کیا کرتے تھے.اس روایت سے یہ حقیقت بھی روشن ہوتی ہے کہ صحابہ براہِ راست رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کی
تعلیم حاصل کیا کرتے تھے.واقعہ کچھ یوں ہے:
Page 67
عہد نبوی میں جمع و تدوین قرآن
51
حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ایک صحابی
ہشام بن حکیم بن حزام ( رضی اللہ عنہ ) کو سورۃ الفرقان کی تلاوت کرتے سنا.میں نے غور سے سُنا
تو معلوم ہوا کہ وہ کسی ایسے انداز میں پڑھ رہے ہیں جس انداز میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نے مجھے کبھی نہیں پڑھایا.پس میں ان
کی نماز مکمل ہونے کا انتظار کرتا رہا اور مجھے ان کی نماز کے
اختتام تک بہت صبر سے بیٹھنا پڑا.جب انہوں نے سلام پھیرا تو میں نے ان کو ان کی چادر سے
پکڑ لیا اور پوچھا کہ جو سورۃ میں نے ابھی تجھ سے سنی ہے یہ تجھے کس نے پڑھائی ہے.انہوں نے
جواب دیا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی ہے.میں نے کہا تم غلط کہتے ہو کیونکہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھی پڑھائی ہے اور وہ اس طرح نہیں ہے.پس میں انہیں لے
رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ میں نے انہیں قرآن کریم
اس انداز میں پڑھتے ہوئے سُنا ہے جو آپ نے مجھے نہیں پڑھایا.اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا اسے چھوڑ دو اور کہا اے ہشام پڑھو.پھر مجھے پڑھنے کا ارشاد فرمایا.پس میں نے
اسی طرح تلاوت کی جس طرح میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے سیکھی تھی.اس پر
رسول کریم نے فرمایا کہ ( یہ سورۃ ) اس طرح بھی نازل ہوئی ہے.پھر فرمانے لگے کہ قرآن کریم
سات حروف میں نازل ہوا ہے پس جیسے آسانی محسوس کرو، پڑھ لیا کرو.(بخاری کتاب فضائل القرآن باب انزل القرآن على سبعة حرف)
اس روایت کے مطابق دونوں صحابہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے قرآن کریم سیکھا تھا.اسی طرح
مسند احمد بن حنبل میں روایت ہے کہ ایک انصاری صحابیہ حضرت ام ہشام فرماتی ہیں:
أَخَذْتُ قَ وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ (ق:2) عَلَى لِسَانٍ رَسُولِ الله الله
(مسند القبائل حديث ام هشام بن حارثه النعمان)
یعنی میں نے سورۃ ق آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سیکھی تھی.عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صلى الله عليه و وسلم لِأُبَيِّ
بنِ كَعْب "إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأْ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ - قَالَ: اللَّهُ سَمَّانِي لَكَ
قَالَ : نَعَمْ قَالَ : وَقَدْ ذُكِرْتُ عِنْدَ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ قَالَ نَعَمْ - فَذَرَفَتْ عَيْنَاهُ
(متفق عليه بحواله مشكاة المصابيح كتاب فضائل القرآن)
حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابيِّ بِنُ كَعب
رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم کو قرآن پڑھ کر
Page 68
الذكر المحفوظ
52
سناؤں.حضرت ابی بن کعب نے عرض کی کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لے کر آپ
کو یہ حکم دیا
ہے.آنحضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا ہاں اُبی بن كَعْب نے عرض کی ، یا رسول اللہ! کیا
آپ نے رب العالمین کے حضور میر اذ کر کیا تھا ؟ اس پر آنحضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا،
ہاں.آنحضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا جواب سن کر ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی آنکھیں
ڈبڈبا آئیں.آنحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی قرآن کریم کی درس و تدریس میں مشغول رہنے والوں سے محبت کا یہ عالم
تھا کہ تاریخ میں اس واقعہ کا ذکر ملتا ہے کہ ایک مرتبہ آنحضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے تو
دیکھتے ہیں کہ صحابہ کے دو گروہ بنے ہوئے ہیں.ایک گروہ عبادات اور دعاؤں وغیرہ میں مصروف ہے اور
دوسرے گروہ میں قرآن کریم کی تعلیم و تدریس کا سلسلہ جاری ہے.آنحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم فرمانے لگے
کہ مجھے تو معلم بنا کے بھیجا گیا ہے اور پھر آپ قرآن کریم کی تعلیم و تدریس میں مشغول گروہ میں رونق افروز ہو گئے.مقدمه سنن ابن ماجه باب فضل العلماء و الحث على طلب العلم
پھر صحابہ کرام کو قرآن کریم کی تعلیم دینے کے لیے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے چار صحابہ
رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارہ میں یہ حکم فرمایا کہ ان سے قرآن سیکھو.چنانچہ روایات میں ذکر ملتا ہے:
النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا القرآن من اربعة من عبدالله بن
مسعود و سالم و معاذ بن جبل و أبي بن كعب
صلہ الله
(بخاری کتاب فضائل القرآن باب القراء من اصحاب النبي
عا وسلم
آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ چار افراد سے قرآن کریم کی تعلیم حاصل کیا کرو.عبد الله بن مسعود، سالم، معاذ بن جبل اور ابی بن کعب (رضوان اللہ علیہم اجمعین )
لمصل
حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب خلیفتہ اسیح الثانی الصلح الموعود رضی اللہ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کے اس عمل کی حکمت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان اساتذہ میں سے دومہاجرین میں سے تھے اور دو
انصار میں سے.دور و سا میں سے تھے اور ایک مزدور اور ایک تاجر تھے.گویا ہر طبقے کے لیے معلم کا انتظام کر دیا.(دیباچہ تفسیر القرآن ضیاء الاسلام پر یس ربوہ صفحہ 271)
صرف انصار مدینہ میں سے ستر حفاظ کی شہادت کے واقعہ کا ذکر ( صفحہ 28 پر ) گزرا.اس کے علاوہ بھی
اور بہت سے واقعات ملتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم مختلف قبائل میں دس دس پندرہ پندرہ قراء
صحابہ کے وفود تعلیم القرآن کے لیے بھیجا کرتے تھے.مہاجرین اور انصار دونوں میں حفاظ کی کثیر تعداد موجود تھی
جو آنحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرتے اور پھر وفود کی صورت میں عرب کے مختلف
Page 69
عہد نبوی میں جمع و تدوین قرآن
53
علاقوں میں جا کر رہتے اور دیگر مسلمانوں کو قرآن کریم کی تعلیم دیتے تھے.اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آنحضر
صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر نگرانی مدینہ منورہ کے مرکزی نظام کے تحت براہ راست سارے مسلم عرب کی تعلیم
القرآن کی ضروریات پوری کی جارہی تھیں.صحاح ستہ میں نیز دیگر حدیث اور تاریخ کی کتب میں با قاعدہ تعلیم القرآن اور تفسیر القرآن کے ابواب ہیں.جن میں تعلیم القرآن کے سلسلہ میں آنحضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی مساعی کا ذکر اور قرآن کریم سے محبت اور اس
کی تعلیم حاصل کرنے کا شوق اور رغبت پیدا کرنے کے لیے آپ کی نصائح درج ہیں.تعلیم قرآن کے سلسلہ میں آنحضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کس قدر باریک بینی سے انتظام فرماتے تھے اس کا
اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ آپ کو یہ خیال رہتا تھا کہ صرف آپ کی خوشنودی کی خاطر ہی صحابہ تعلیم القرآن
میں مصروف نہ رہیں بلکہ خدا کی رضا اور قرآن کریم کی تعلیم کی اہمیت کی خاطر اس میدان میں آگے قدم ماریں.تا کہ ایسا نہ ہو کہ جب آپ سامنے نہ ہوں تو تعلیم القرآن کا سلسلہ ستی یا کمزوری کا شکار ہوجائے.مثلاً روایت ہے:
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّنْ بُيُوتِ اللَّهِ
يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ وَيَتَدَارَسُوْنَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ
وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ
(سنن ابی داود کتاب الوتر باب في ثواب قراءة القرآن)
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا جب بھی
کوئی قوم قرآن کریم پڑھنے کے لیے اور ایک دوسرے کو پڑھانے کے لیے خدا تعالیٰ کے
گھروں میں سے کسی گھر میں اکٹھی ہوتی ہے تو ان پر سکینت نازل ہوتی ہے اور رحمت ان کو
ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے ان کے گرد حلقہ بنا لیتے ہیں.اس روایت سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ مساجد میں بھی تعلیم القرآن کی با قاعدہ کلاسز منعقد ہوا کرتی تھیں.اسی طرح تاریخ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مساجد کے علاوہ صحابہ کے گھروں میں بھی تعلیم القرآن کلاسز کا
با قاعدہ انعقاد ہوا کرتا تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم انکی نگرانی بھی فرمایا کرتے اور حوصلہ افزائی فرمایا
کرتے تھے.چنانچہ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ الاشعری کے گھر پر جاری تعلیم
القرآن کلاس کے معائنہ کی خواہش کا اظہار فرمایا کہ کیا ایسا انتظام ہوسکتا ہے کہ میں وہاں جا کر بیٹھوں اور کسی کو
میری موجودگی کا علم نہ ہو؟ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کو ایک ایسے اندھیرے کونے میں اس طرح بٹھا دیا
گیا کہ آپ تو سب کو دیکھ سکتے تھے مگر آپ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا.آپ نے کلاس کا جائزہ لیا اور اگلے روز اپنی
Page 70
الذكر المحفوظ
54
خوشنودی کا اظہار فرماتے ہوئے حضرت ابو موسی الاشعری سے فرمایا:
لو رأيتني و انا استمع لقرائتك البارحة لقد اوتيت مزمارا من مزامير آل داؤد
(مسلم کتاب صلاة المسافرين قصرها باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن)
یعنی آپ نے تو مجھے نہیں دیکھا لیکن میں نے گزشتہ رات آپ کی تلاوت سنی.آپ کو تو آل داؤد
جیسا خوبصورت لحن دیا گیا ہے.حضرت ابو موسیٰ اشعری روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا : ایسا مومن
جو قرآن پڑھتا ہے اور اس پر عمل پیرا ہوتا ہے سنگترے کی طرح ہے.اس کا ذائقہ بھی اچھا ہوتا
ہے اور اس کی خوشبو بھی اچھی ہوتی ہے اور ایسا مومن جو قرآن نہیں پڑھتا لیکن اس پر عمل پیرا ہوتا
ہے وہ کھجور کی طرح ہے جس کا ذائقہ تو لذیذ ہوتا ہے لیکن اس میں خوشبو نہیں ہوتی اور قرآن
پڑھنے والے منافق کی مثال ریحان (نیاز بو) کی طرح ہوتی ہے جس کی خوشبو تو اچھی ہوتی ہے
لیکن اس کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے اور قرآن نہ پڑھنے والے منافق کی مثال حنظل یعنی حمہ کی طرح
ہوتی ہے جس کا ذائقہ بھی کڑوا ہوتا ہے اور خوشبو بھی ناگوار ہوتی ہے.(بخاری کتاب فضائل القرآن باب اثم من راى بقراة القرآن او تاکل به او فخربه)
آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے والوں کو نصائح بھی فرمائیں.عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " مَا مِنْ أَمْرِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ ثُمَّ
يَنْسَاهُ إِلَّا لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَجْدَمُ ،
66
(سنن ابی داود کتاب الوتر باب التشديد فيمن حفظ القرآن ثم نسيه)
سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا:
جو آدمی قرآن کریم پڑھ کر بھول جاتا ہے تو وہ قیامت کے دن خدا تعالیٰ کے حضور اس
66
حالت میں حاضر ہوگا کہ اس کی صورت بگڑی ہوئی ہوگی.“
عَنْ سَهْلِ بْنِ مَعَادٍ الْجُهَنِيِّ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه و سلم
قَالَ: مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَعَمِلَ بِمَا فِيهِ الْبسَ وَالِدَاهُ تَاجًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ضَوْءُ هُ
أَحْسَنُ مِنْ ضَوْءِ الشَّمْسِ فِي بُيُوتِ الدُّنْيَا لَوْ كَانَتْ فِيْكُمْ فَمَا ظَنُّكُمُ
بِالَّذِي عَمِلَ بِهَذَا.(سنن ابی داود کتاب الوتر باب ثواب قراءة القرآن)
سهل بن مُعَاذَ جُہنِی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
Page 71
عہد نبوی میں جمع و تدوین قرآن
55
نے فرمایا ، جس شخص نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا تو قیامت کے روز اس کے ماں باپ کو دو
تاج پہنائے جائیں گے جن کی روشنی سورج کی چمک سے بھی زیادہ ہو گی جو ان کے دنیا کے
گھروں میں ہوتی تھی پھر جب اس کے والدین کا یہ درجہ ہے تو خیال کرو کہ اس شخص کا کیا درجہ
ہوگا جس نے قرآن پر عمل کیا.حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم قرآن کریم کا زیادہ علم رکھنے والے کو دوسرے اصحاب پر فضیلت
دیتے تھے.چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ رسول کریم امامت اور قیادت کی سپردگی کے وقت یہ خاص خیال رکھتے
تھے کہ قرآن کریم کا علم کس کے پاس زیادہ ہے.اسی طرح جب جنگ احد میں شہدا کی تدفین کا مرحلہ آیا تو
آنحضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے ان صحابہ کو دفن کر و جو قرآن کریم کا زیادہ علم رکھتے تھے.گویا
وفات کے بعد بھی عالم قرآن کی عزت قائم رکھی گئی ہے.(بخاری کتاب الجنائز باب الصلاة على الشهيد)
عَنْ عُثمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَن النَّبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: خَيْرُكُمْ
مَّنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ
(بخاری کتاب فضائل القرآن باب : خيركم من تعلم القرآن وعلمه)
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا، تم
میں سے بہترین وہ شخص ہے جو خود قرآن سیکھتا اور دوسروں کو اس
کی تعلیم دیتا ہے.عَنْ عُثْمَانَ بْن عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : إِنَّ
أَفْضَلَكُمْ مَّنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ
(بخاری کتاب فضائل القرآن باب : خيركم من تعلم القرآن وعلمه)
حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے
فرمایا تم میں سے افضل وہ ہے جو خود قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو قرآن سکھاتا ہے.عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الَّذِي يَقْرَأُ
الْقُرْآنَ وَهُوَ مَاهِرٌ بِهِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ -
(ترمذی کتاب فضائل القرآن باب ماجاء في فضل قارئ القرآن)
ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے
فرمایا، وہ شخص جو قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اور اس میں عبور رکھتا ہے وہ فرمانبردار اور معزز
سفر کرنے والوں کے ساتھ ہوگا.
Page 72
الذكر المحفوظ
56
حَدَّثَنِيْ عَامِرُ بْنُ وَايْلَةَ أَنَّ نَافِعَ بُنَ عَبْدِ الْحَارِثِ لَقِيَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ
بِعُسْفَانَ وَكَانَ اسْتَعْمَلَهُ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ - فَسَلَّمَ عَلَى عُمَرَ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ:
اسْتَخْلَفْتَ عَلَى أَهْلِ الْوَادِى فَقَالَ نَافِعٌ - : اِسْتَخْلَفْتُ عَلَيْهِمُ ابْنُ
أَبْرَى فَقَالَ عُمَرُ وَ مَنْ اِبْنُ أَبْرَى؟ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّهُ لَقَارِيٌّ
لِكِتَابِ اللَّهِ عَالِمٌ بِالْفَرَائِضِ فَقَالَ عُمَرُ: أَمَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ قَالَ إِنَّ
اللهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ
الدارمي كتاب فضائل القرآن باب ان الله يرفع بهذا القرآن اقواما ويضع آخرين)
راوی کہتے ہیں کہ عامر بن واثلہ نے بیان کیا کہ نافع بن عبدالحارث حضرت عمر بن خطاب
رضی اللہ عنہ کو محسفان میں ملے.حضرت عمرؓ نے انہیں اہل مکہ کا والی مقرر کیا ہوا تھا.انہوں نے
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سلام کیا.حضرت عمر نے ان سے دریافت فرمایا کہ آپ نے مکہ میں اپنا
قائم مقام کس کو مقرر کیا ؟ نافع نے کہا.میں نے ابنِ ابی کو اپنے قائم مقام کے طور پر مقرر کیا
ہے.حضرت عمرؓ نے دریافت فرمایا.ابنِ انبری کون ہے؟ نافع نے عرض کی.اے امیر المومنین !
وہ حافظ قرآن اور علم الفرائض کے ماہر ہیں.اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تمہارا
فیصلہ درست ہے.رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے طفیل بعض
لوگوں کا مقام و مرتبہ بڑھائے گا اور بعض کو مقام و مرتبہ میں گرادے گا.اسی طرح ایک دوسرے مقام پر رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم قرآن
کریم کا علم حاصل کرنے والوں کا مرتبہ
ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں:
حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ
اہل اللہ ہوتے ہیں.راوی کہتا ہے اس پر آپ سے دریافت کیا گیا.یا رسول اللہ ! اہل اللہ کون
ہوتے ہیں؟ آنحضور نے فرمایا.قرآن والے اہل اللہ اور اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں.(مسند احمد بن حنبل جلد 3 صفحه 128 مطبوعه بيروت)
رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم اور آپ کے جانثار صحابہ کے اس اسوہ پر چلتے ہوئے اسلام کے ابتدائی دور
سے لے کر اب تک امت محمدیہ کا نمونہ تو دنیا کے سامنے ہے ہی کہ کس طرح بچے کو چھوٹی عمر سے قرآن کریم کی تعلیم
دی جاتی ہے.آنحضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی جاری کردہ سنت کے عین مطابق آج تک تواتر کے ساتھ تعلیم القرآن
اور حفظ کا سلسلہ جاری ہے.تعلیم القرآن اور حفظ قرآن کے مدر سے شہر شہر اور گاؤں گاؤں میں قائم ہیں.دیہات ، قصبات اور شہروں میں چھوٹے جھوٹے مدرسوں کے علاوہ سکولوں کالجوں اور بڑی بڑی اسلامی اور
Page 73
عہد نبوی میں جمع و تدوین قرآن
57
غیر اسلامی یونیورسٹیوں میں بھی قرآن کریم کی تعلیم کا سلسلہ جاری ہے.آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں قرآن کریم کا متن محفوظ تھا اور تمام صحابہ کی پہنچ میں تھا اس کی ایک
قومی گواہی حجتہ الوداع کے موقع پر ساری امت نے دی جب آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام حاضرین کو مخاطب
کر کے
فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں خدا کا پیغام پہنچا دیا ہے.لاکھوں کے اس مجمع نے یک زبان ہو کر اس حقیقت کا
اعتراف کیا اور آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں گواہی دی.اگر قرآن کریم تحریری صورت میں اور حفظ کی صورت
میں محفوظ نہ ہوتا اور تعلیم القرآن کا کما حقہ اہتمام نہ ہوتا تو اُس وقت ضرور یہ سوال اُٹھتا کہ یہ کس طرح کہا جاسکتا ہے
کہ پیغام قوم تک پہنچ گیا جب کہ وحی الہی نہ تحریری صورت میں موجود ہے اور نہ ہی امت میں عام طور پر اس کی
تعلیمات رائج ہیں ؟ لاکھوں
کا وہ مجمع تبھی گواہی دے سکتا تھا جب اُن میں سے ہر ایک کو علم ہوتا کہ قرآن کریم اس کی
پہنچ میں ہے.اب اُس کی تعلیمات سے
فائدہ اُٹھانایا نہ اٹھانا ان کی صوابدید پر ہے.اب ایک طرف تدوین قرآن کے ضمن میں کی جانے والی ان مساعی کو دیکھیں اور دوسری طرف اعتراض کو
دیکھیں جو اُٹھایا جارہا ہے کہ:
The Prophet himself may have forgotten some verses,
the companions` memory may have equally failed them,
and the copyists may also have mislaid some verses.We
also have the case of the Satanic Verses, which clearly
shows that Muhammad himself suppressed some verses.(Ibn Warraq: Why I am Not A Muslim, Prometheus Books, New
York, 1995, under heading; The Koran: Pg112)
یعنی ہو سکتا ہے نبی (ع) خود کچھ آیات بھول گئے ہوں.ہوسکتا ہے حفظ کرنے والے کچھ
آیات بھول گئے ہوں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کاتبین نے کچھ آیات غلط طور پرلکھ دی ہوں پھر ہمارے
پاس شیطانی آیات کا قصہ ہے جو یہ بتاتا ہے
کہ محمد (ﷺ) نے کچھ آیات خود بھی چھپالی ہیں.یہاں ابن وراق نے قاری کے دل میں یہ شک ڈالنے کی کوشش کی ہے کہ جس طرح تمام مذاہب کی تاریخ
شکوک وشبہات سے پُر ہے یہی حال اسلامی تاریخ کا بھی ہے.کچھ یقین سے نہیں کہا جاسکتا کہ کیا ہوا ہو گا.بہت
سے امکانات ہیں کہ ہوسکتا ہے فلاں حادثہ ہو گیا ہو یا فلاں حادثہ ہو گیا ہو.حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے.گزشتہ سطور
میں حفاظت قرآن کے حوالہ سے تو ہم دیکھ آئے ہیں کہ اسلامی تاریخ تو چمکتے سورج کی طرح روشن اور واضح ہے اور
اس میں ہر چیز ایسی واضح ہے جیسے دن کی روشنی میں.چنانچہ حقین اس کا کھل کر اعتراف کرتے ہیں.باسورتھ سمتھ
دوسرے مذاہب کا تاریخی لحاظ سے غیر مستند اور کمزور ہونا بیان کرنے کے بعد اسلام کے بارہ میں لکھتے ہیں:
But in Mohammedanism every thing is different here,
instead of the shadowy and mysterious, we have his story.
Page 74
58
الذكر المحفوظ
We know as much of Mohammed as we do even of Luther
and Milton.The mythical, the legendary, the supernatural
is almost wanting in the original Arab authorities, or at all
events can easily be distinguished from what is historical.Nobody here is the dupe of himself or of others; there is
the full light of day upon all that light can ever reach at all.(Basworth Smith "Mohammad and Mohammadanism" London
1874, p.41,42)
محمدن ازم میں معاملہ ( دوسرے مذاہب سے ) بالکل مختلف ہے.یہاں ہمارے پاس
اندھیروں کی بجائے تاریخ کی روشنی ہے.ہم آپ کے بارہ میں اتنا ہی جانتے ہیں جتنا کہ لوتھر
اور ملٹن کے بارہ میں.یہاں حقائق ہیں نہ کہ خیالات اور قیاسات اور ظنون اور طلسماتی
کہانیاں.ہم بآسانی معلوم کر سکتے ہیں کہ اصل حقیقت کیا ہے.ان معاملات میں نہ تو کوئی
شخص خود کو دجل اور فریب میں مبتلا کر سکتا ہے اور نہ کسی اور کو.یہاں ہر چیز دن کی پوری روشنی
میں جگمگا رہی ہے.اسی طرح فلپ کے حتی بھی کہتے ہیں کہ اسلام کی تاریخ میں کوئی اہم بات شک وشبہ کا شکار نہیں ہے بلکہ
ظاہر وباہر ہے:
تاریخ عرب از فلپ کے حتی ، ناشر : آصف جاوید برائے نگارشات ، باب 4 صفحہ 21)
مشہور رومن کیتھولک نن اور مشرقی علوم کی ماہر کیرم آرم سٹرانگ اسلامی تاریخ کے ابتدائی ماخذ اور مشہور
مسلمان مؤرخین ابن اسحق ، ابن سعد، طبری اور واقدی کے بارہ میں بھتی ہیں:
یہ چاروں بہت معتبر مؤرخ اور سوانح نگار ہیں.ان سوانح نگاروں کے ہاں آپ
کو محض ان کے
خیالات اور معتقدات ہی نہیں ملتے بلکہ حقائق کو تلاش کرنے کی محققانہ کاوش بھی دکھائی دیتی ہے.مثلاً
انہوں نے تمام ابتدائی اور بنیادی دستاویزات کو پڑھا، سینہ بسینہ چلی آرہی روایات و حکایات کو سنا اور
اس کے باوجود کہ وہ سچے مسلمان تھے اور نبی کریم (ع) کی ذات مبارک سے گہری عقیدت رکھتے
تھے، تاریخ لکھتے ہوئے کم ہی دکھائی دیتا ہے کہ وہ کسی معاملہ میں جانب دار ہوئے ہوں....ان
سوانح عمریوں کی درستگی پر اعتبار کرتے ہوئے ہم یہ بات پورے وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ ان کی بنیاد پر
ہم نبی (ﷺ) کی حیات مبارکہ کا ایک زیادہ حقیقت پسندانہ اور سچا خا کہ حاصل کر سکتے ہیں.ان مؤرخین کے انداز تحقیق وتحریر سے ظاہر ہے کہ وہ اس موضوع پر کام کرنے والے دیگر جدید
مغربی مؤرخین سے بے حد مختلف ہیں.اپنی کتب میں انہوں نے بہت سے غیر معمولی اور کافی حد
تک ایسے نا قابل یقین واقعات بھی شامل کیے ہیں جنہیں ہم آج بہت مختلف انداز میں بیان کریں
Page 75
59
عہد نبوی میں جمع و تدوین قرآن
گے.لیکن وہ معاملات کی پیچیدگی اور سچائی کی باریک اور مہم نوعیت سے کما حقہ آگاہ تھے.وہ کسی
ایک نظریے کی بنیاد پر کسی دوسرے نظریے کو ثابت یا واقعہ کی وضاحت نہیں کرتے بلکہ بعض اوقات وہ
مختلف طریقہ کار اختیار کرتے ہیں.وہ ایک ہی روایت کی ایک سے زیادہ معروف صورتیں پیش
کر دیتے ہیں اور ان میں سے کسی ایک کی درستگی کے بارے میں کوئی رائے نہیں دیتے اور نہ اس ضمن
میں قارئین کی رائے کو متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں.یہ اور بات ہے کہ ہم آج انہیں کن
معیارات پر پرکھیں.اُس دور میں جس حد تک ان سے ممکن تھا انہوں نے ہر ایک واقعہ کو انتہائی تفصیل
اور ثبوت کے ساتھ پیش کیا ہے.تاہم بہت سے موقعوں پر وہ اس بات کو واضح بھی کرتے ہیں کہ وہ خود
بھی پیش کردہ واقعے یا ثبوت سے متفق نہیں ہیں.اس سے یہ بات اظہر من الشمس ہو جاتی ہے کہ اس
کے باوجود کہ ان مؤرخین کی پیغمبر اسلام کی ذات مبارکہ سے گہری عقیدت تھی، انہوں نے آپ کی
زندگی کی تفصیلات کو ممکنہ حد تک درست اور ٹھوس دلائل اور شواہد کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کی ہے.محمد ( ﷺ ) باب دوم ، صفحہ 59, 58 پبلشرز علی پلاز 30 مزنگ روڈ لاہور )
پھر بذات خود اعتراض کا بھونڈا پن بھی ظاہر ہے.قرآن کریم کی حفاظت کے ذکر میں تاریخی ثبوتوں اور نا قابل
تردید دلائل کے ساتھ بیان ہو چکا ہے کہ حفاظت کا ایسا غیر معمولی اہتمام کیا گیا ہے کہ تاریخ انسانی میں اور کوئی مثال نہیں
ملتی کہ اس شان اور اہتمام کے ساتھ کسی بھی چیز کی حفاظت کی گئی ہو اور اعتراض کیا ہے؟!!’ہوسکتا ہے“ گویا کوئی طفل
مکتب یا نا واقف انسان ہے، جسے قرآن کریم کی تاریخ سے ادنی سا بھی مس نہیں اور جو یہ سمجھتا ہے کہ قرآن کریم کے بارہ
میں نہیں بلکہ کسی عام سی کتاب کے بارہ میں بات ہو رہی ہے.پس اس سوال کا اتنا جواب ہی کافی ہے کہ یہ دراصل
تمہاری حسرتیں ہیں نہ کہ حقیقت.اگر ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے تو ثبوت کے ساتھ پیش کرو.پس یہ کیسا محقق ہے جو اتنے دلائل اور ثبوتوں کو دیکھ کر بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ہوسکتا ہے یہ ہو گیا ہو اور وہ ہو گیا ہو؟
لگتا ہے تاریخ اسلام میں حفاظت قرآن کے سلسلہ میں روشن ثبوتوں کی آب و تاب سے اسکی آنکھیں چندھیا گئی
ہیں اور ایک ہی طریقہ بچا ہے اعتراض کو آگے بڑھانے کا کہ روز روشن میں اندھے کی طرح ٹھوکریں کھاتے
ہوئے آگے بڑھا جائے.بات کی جائے کہ ” ہو سکتا ہے آخر اعتراض کرنے کی جلدی کیا تھی ؟ کون سی گاڑی
چھوٹ رہی تھی ؟ تھوڑی سی تحقیق کر لیتے پھر اگر اعتراض کا کوئی پہلو نظر آتا تو بیان کرتے اور اگر جاہلانہ روش ہی
اختیار کرنی تھی تو پھر علمی میدان میں آئے ہی کیوں.یہ تو ایسی ہی بات ہے کہ جیسے کسی معز محفل میں کوئی دیوانہ
چلا نا شروع کر دے.جہاں واضح حقائق نظر آرہے ہوں وہاں جان بوجھ کر اندھے پن کا ثبوت دینا اور یہ کہنا
ایک دیانت دار محقق کو زیب نہیں دیتا کہ ہو سکتا ہے یہ ہو گیا ہو.ہوسکتا ہے وہ ہو گیا ہو.
Page 76
الذكر المحفوظ
60
قرآن کریم حافظہ سے محو نہ ہونے دینا خدا تعالی کی ذمہ داری تھی
اب تک تو یہ بات ہو رہی تھی کہ تاریخی شہادتیں اور مستند ثبوت سب اسی بات پر متفق ہیں کہ قرآن کریم
آنحضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے بعینہ ویسے ہی ہم تک پہنچایا ہے جیسا کہ آپ کے سپرد کیا گیا اور ان حالات میں
کسی بشری کمزوری کی وجہ سے اس کا کوئی حصہ ضائع ہونا ناممکن تھا.لیکن اس بحث کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جب
خدا نے بنی نوع کی ہدایت کا سامان فرمانا ہی تھا تو پھر لازماً پورا سامان فرمانا تھا نہ کہ ادھورا چھوڑ دیتا اور اپنے فعل کو
اپنی نگاہوں کے سامنے برباد ہوتے دیکھتا.جب ہدایت کا بیڑا اٹھایا تھا تو پھر لا محالہ ایسے سامان بھی بہم پہنچانے
تھے کہ اس کا پیغام بلا کم کاست اور بلا شک وشبہ بنی نوع تک پہنچتا.ناممکن تھا کہ اپنے ایک بابرکت سلسلہ کو مقصد
پورا کیے بغیر اپنی آنکھوں کے سامنے ضائع ہوتے دیکھتا اور خاموش رہتا.خاص کر اس صورت میں کہ اس سلسلہ کی
حفاظت کا وعدہ بھی لے رکھا تھا اور پھر اس حفاظت پر پوری طرح قادر بھی تھا.یہ امر بھی واضح ہے کہ جب خدا تعالیٰ نے ایک کام کے لیے آنحضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کو چنا تھا تو پھر اپنے
ارادہ کی تکمیل کے لیے آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کو لازماً ایسے قومی اور صلاحیتیں بھی دینی تھیں.جب دُنیا تک اپنا
کلام پہنچانے کے لیے آپ کو چنا تھا تو لازماً آپ کو وہ تمام صلاحیتیں بتمام و کمال عطا کرنی تھیں جو قرآن کریم کو
بعینہ آگے منتقل کرنے کے لیے ضروری تھیں.عقلی لحاظ سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ خدا تعالیٰ جو اتنا عظیم الشان
سلسلہ انبیاء قائم کرتا ہے اور ایک انقلاب ان کے ذریعے پیدا کرتا ہے تو یہ سب تبھی ممکن ہے کہ جب خدا تعالیٰ کی
تعلیم بلا کم و کاست اس کی مخلوق تک پہنچے.پس کیونکر ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ لاکھوں کروڑوں انسانوں میں سے ایک
کا انتخاب کرے اور وہ منتخب انسان اس قابل ہی نہ ہو کہ اس پیغام کو آگے پہنچا سکے اور پھر اس منتخب انسان پر اپنا
کلام نازل کرے مگر اس کو ایسے قومی ہی نہ دے کہ وہ خدا کا مامورا سے دُنیا تک پہنچا سکے.پس ضرور خدا تعالیٰ اس
کلام کی حفاظت کا انتظام فرماتا ہے اور عقل اس بات کو تسلیم ہی نہیں کر سکتی کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں انقلابی تبدیلیاں
پیدا کرنے کے لیے لاکھوں، کروڑوں انسانوں میں سے کسی ایک کو ساری دُنیا کی اصلاح کے لیے چنے اور پھر
اُسے ایسے کمزور قومی عطا کرے کہ وہ ہر بات بھول جائے اور خود ہی شبہات کا شکار رہے اور خدا تعالیٰ اپنے سلسلہ
کے شروع میں ہی خاموشی سے اسکی بربادی کا تماشا دیکھتا ر ہے.وہ قادر مطلق اور ہادی خدا تو حفاظت کی خاطر
ایسے ایسے انتظامات فرماتا ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے اور حامل وحی کو وہ ذہن رسا اور عظیم قومی عطا کرتا ہے جو اس کلام
کا بوجھ سہارنے کے ساتھ ساتھ اسکی محافظت کے لیے ضروری ہوتے ہیں.حضرت مرزا طاہر احمد خلیفہ اسیح الرابع رحمہ اللہ فرماتے ہیں:
Again the person deemed fit by God to represent Him
Page 77
61
عہد نبوی میں جمع و تدوین قرآن
is always of this trust because of his absolute adherence to
truth.As such it is impossible for him to commit injustice
either in relation to God or His massage or in relation to
mankind.But this only happens when the faculty of such a
person have been cultivated by God to reach a stage of
perfect proportion and poise; and then is he considered fit.by God to act as His messenger.God thereby, places His
trust in him and this trust is never betrayed.(Absolute Justice Part 1, Under Heading No.8 "The Role of the
Three Creative Principles in the Shaping of Religion
Page:117-118)
خدا تعالی کی نمائندگی کا استحقاق اسی کو ہوتا ہے جو سچائی کے ساتھ کامل وابستگی کی بدولت
ہمیشہ خدا تعالیٰ کا معتمد ہوتا ہے.چنانچہ ناممکن ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیغام کے تعلق میں
بنی نوع انسان کے ساتھ کسی بھی قسم کی نا انصافی کا مرتکب ہو.اللہ تعالیٰ اس کی تمام صلاحیتوں کو
ایک کامل تناسب اور توازن کے کمال تک پہنچانے کے بعد ہی اسے نبوت کے اعلیٰ مقام پر سرفراز
کیا کرتا ہے اور اپنا کام اعتماد سے عطا فرماتا ہے اور وہ بندہ کبھی بھی اس اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچا تا.چنانچہ اسی حقیقت کی طرف اللہ تعالیٰ ان الفاظ میں اشارہ کرتا ہے:
وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى 0
ذُومِرَّةٍ ط فَاسْتَوَى (النجم : 4 تا 7)
ترجمہ: اور وہ خواہش نفس سے کلام نہیں کرتا.یہ تو خالصہ ایک وحی ہے جو اُتاری جارہی
ہے.اسے مضبوط طاقتوں والے نے سکھایا ہے.(جو) بڑی حکمت والا ہے.پس وہ فائز ہوا.ان آیات میں عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوی کے الفاظ میں یہ واضح طور پر فرما دیا کہ اس حفاظت کے تعلق میں جہاں
تک رسول
کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق کا تعلق ہے تو انہیں اس شان کے قومی جو قرآن کے محفوظ رکھنے کے لیے
درکار ہیں، خدا تعالیٰ نے عطا کرنے ہیں.آنحضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے غیر معمولی قومی کے بارہ میں آپ کی
سیرت کا مطالعہ کرنے والے آج بھی گواہ ہیں.واشنگٹن آئر ونگ یہ شہادت ان الفاظ میں دیتے ہیں:
"His intellectual qualities were undoubtedly of an
extraordinary kind.He had a quick apprehension, a
retentive memory, a vivid imagination and an inventive
genius."
(Washington Irving: Mahomet and his Successors, Printers: George
Bell & Son Londons, York St., Covet Garden, 1909, p.192)
آپ ﷺ کی ذہنی صلاحیتیں بلاشبہ غیر معمولی نوعیت کی تھیں.تیز تر فراست، بلا
Page 78
الذكر المحفوظ
کا حافظہ غضب کی ذہانت اور تخلیقی سوچ.ایڈورڈگن رقم طراز ہیں:
62
"His (i.e., Muhammad's) memory was capacious and
retentive, his wit easy and social, his imagination
sublime, his judgment clear, rapid and decisive.He
possessed the courage of both thought and action; and...the first idea which he entertained of his divine mission
bears the stamp of an original and superior genius."
(Edward Gibbon: The History of the Decline and Fall of the
Roman Empire, John Murray, Albemarle St.London 1855, vol.6,p335
یعنی آپ کا حافظہ وسیع اور تیز ، آپ کا فلسفہ عام فہم ، آپ کا تصور بلند پایہ، آپ کا فیصلہ
واضح، تیز اور درست، آپ کو قول اور فعل دونوں کی جرأت عطا کی گئی تھی.اور اپنے الوہی
مشن کے بارہ میں پہلا نظریہ جو آپ نے قائم کیا وہ ایک حقیقی اور بلند تر سوچ کی حامل ہستی کی
طرف سے ہونے کا ثبوت اپنے ساتھ رکھتا تھا.اور پھر بذات خود خدا تعالیٰ شدید القویٰ ہے.جب وہ ایک کام کا ارادہ کر لیتا ہے تو کوئی دوسری طاقت یا کسی
کی کمزوری خدا کے کے ارادہ کے پورا ہونے میں روک نہیں بن سکتی.پس ان بشری کمزوریوں سے قرآن کریم کو
بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جمع قرآن کا تمام کام اپنے ذمہ لے رکھا تھا اور آپ کو اس امانت کا اہل بنانے کے
لیے تمام ضروری قو می بھی عطا کیے تھے.چنانچہ جب قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری کے احساس سے آپ صلی اللہ
علیہ والہ وسلم وحی الہی کو نزول کے ساتھ ساتھ تیزی سے دہراتے اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں تسلی دیتا ہے کہ:
فَتَعَلَى اللهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلُ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ
وَ قُلْ رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا.(طه:115)
ترجمہ: پس اللہ سچا بادشاہ بہت رفیع الشان ہے.پس قرآن (کے پڑھنے ) میں جلدی نہ کیا
کر پیشتر اس کے کہ اُس کی وحی تجھ پر مکمل کر دی جائے اور یہ کہا کر کہ اے میرے رب ! مجھے علم
میں بڑھا دے.اسی طرح فرمایا:
وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ وَّلَا نَبِيِّ إِلَّا إِذَا تَمَتَّى الْقَى الشَّيْطنُ فِي
أمْنِيَّتِهِ ، فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَنُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ ايَتِهِ طَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ ه (الحج : 53)
Page 79
عہد نبوی میں جمع و تدوین قرآن
63
ترجمہ: اور ہم نے تجھ سے پہلے نہ کوئی رسول بھیجا اور نہ نبی مگر جب بھی اُس نے (کوئی) تمنا
کی (نفس کے ) شیطان نے اس کی تمنا میں (بطور ملاوٹ کچھ ) ڈال دیا.تب اللہ اُسے منسوخ
کر دیتا ہے جو شیطان ڈالتا ہے.پھر اللہ اپنی آیات کو مستحکم کر دیتا ہے اور اللہ دائمی علم رکھنے والا
( اور ) بہت حکمت والا ہے.یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر قرآن کریم یا درکھوانا اللہ تعالی کی ذمہ داری تھی اور دوسری جانب رسول
کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم ظاہری لحاظ سے بھی تمام تر احتیاط برتتے تھے پھر قرآن کریم کی اس آیت کا کیا مطلب
ہے: "سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَى إِلَّا مَاشَاءَ الله ( الا علی: 7,8) یعنی ہم تجھے پڑھا ئیں گے، پس تو نہیں بھولے
گا ،سوائے اس کے جو اللہ چاہے.إِلَّا مَا شَاءَ اللہ سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم کا کچھ حصہ ضرور ایسا ہے
جو رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم بھول گئے ہوں گے.اگر بنظر غور دیکھا جائے تو یہ تو حفاظت قرآن کا ایک اور واضح اور انتہائی تسلی بخش اعلان ہے نہ کہ جائے
اعتراض.ذرا غور کریں کہ فرمایا جارہا ہے کہ ہم تجھے پڑھائیں گے پس تو نہیں بھولے گا مگر جو اللہ چاہئے اور
دوسری جگہ بتا دیا کہ اللہ قرآن کریم کی حفاظت چاہتا ہے.پس إِلَّا مَا شَاءَ اللہ سے یہ مراد ہے اگر اپنی بشری
کمزوری کی وجہ سے کچھ بھولا تو اس وجہ سے قرآن کریم میں کمی بیشی نہیں ہوگی.حفاظت قرآن کا بیڑا اٹھانے والا
تیرا خدا تجھے یاد کروائے گا.جہاں تک تیری بشریت کا تعلق ہے تو حفاظت قرآن کے معاملہ میں تو الوہیت کی
چادر میں لپٹا ہوا ہے اور اس معاملہ میں تیری بشریت کبھی آڑے نہیں آئے گی.تیری بشریت خدا تعالیٰ کے علم میں
ہے اس لیے وہ خود اپنے کلام کی حفاظت کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہے.وہ جانتا ہے کہ حفاظت کے تمام تر تقاضے
پورے کرنا اور آئندہ زمانوں میں بھی حفاظت کرنا ایک انسان کے بس کا کام نہیں.پس جہاں تک تیری بشری
کمزوری کا سوال ہے تو وہ شدید القوی خدا اسے اپنے کلام کی حفاظت کی راہ میں حائل نہیں ہونے دے گا اور تجھے
ایسے قومی عطا فرمائے گا کہ تو اس الہی امانت کا بوجھ اُٹھا سکے اور آئندہ زمانوں میں مومنین کو بھی توفیق دیتا چلا
جائے گا اور اُن کا نگران بھی خود ہی ہوگا.چنانچہ فرمایا:
وَمَا تَكون في شأن و ما تتلوا مِنْهُ مِنْ قُرْآن وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا
عَلَيْكُمْ شُهُوداً إِذْ تُفِيضُوْنَ فِيْهِ (يونس:62)
اور ٹو کبھی کسی خاص کیفیت میں نہیں ہوتا اور اس کیفیت میں قرآن کی تلاوت نہیں کرتا.اسی
طرح تم (اے مومنو!) کوئی (اچھا) عمل نہیں کرتے مگر ہم تم پر گواہ ہوتے ہیں جب تم اس میں
مستغرق ہوتے ہو.
Page 80
الذكر المحفوظ
64
گزشتہ صفحات میں ہم یہی حقیقت تاریخی حقائق کی روشنی میں دیکھتے آئے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے حفاظت کے
اس وعدہ کو کس شان سے پورا کیا اور اپنے شدید القوئی ہونے کا کیسا عظیم الشان ثبوت دیا.پس یہ شبہ إِلَّا مَا شَاءَ اللہ کے عربی محاورہ کونہ سمجھنے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے.عربی زبان میں الا ماشاء
اللہ اور الا قلیل دومحاورے ہیں جن کا مطلب یا تو یہ ہوتا ہے کہ ایسا ہونے کا امکان بہت ہی کم ہے یا یہ کہ
ایسا ہر گز نہیں ہوگا.اب جب خدا تعالیٰ نے ایک معاملہ براہ راست اپنے ہاتھ میں لیا ہے تو لازماً اس محاورہ کا
یہی مطلب اخذ کیا جائے گا کہ اس میں ادنیٰ سی کوتاہی بھی محال ہے.یہ مطلب کیوں کر لیا جاسکتا ہے کہ قرآن
کریم کا جمع اور محفوظ کرنا اور اسے تیری یادداشت سے محو نہ ہونے دینا یہ خدا کا کام ہے اور خدا تعالیٰ یہ ذمہ داری
نبھائے گا ہاں اگر کوئی کوتا ہی ہوگئی تو کچھ کہا نہیں جا سکتا.یہ تو ایک غیر منطقی نتیجہ ہے کیونکہ حفاظت قرآن کا
معاملہ خدا تعالیٰ کے زیر نگرانی انجام پایا ہے اور خدا کی طرف سے کسی غلطی یا کوتاہی یا کمزوری سرزد ہونا_ اس کا
تصور بھی نہیں کیا جاسکتا.اگر کوتا ہی سے مرا د رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشری کمزوری لی جائے تو پھر بھی یہی
نتیجہ نکلتا ہے کہ آپ وحی الہی میں سے کچھ نہیں بھولیں گے کیونکہ خدا کا ارادہ وحی کو محفوظ کرنے کا ہے اور کوئی ادنیٰ
بشری کمزوری خدا کے راستے میں روک نہیں بن سکتی.پس یا تو آپ کلام الہی میں سے کچھ بھی نہیں بھولیں گے.یا اگر آپ بتقاضائے بشریت کبھی کچھ بھولیں گے تو آپ کی بھول خدا کے ارادہ حفاظت کی راہ میں روک نہیں
بن سکے گی.پس وہ ضرور آپ کو یاد کروادے گا.پس اس کے معنے یہ ہونگے کہ قرآن کریم کا جمع اور محفوظ کرنا
اور اسے تیری یاداشت سے محو نہ ہونے دینا یہ خدا کا کام ہے اور اس میں کسی بھی قسم کی کوتاہ ممکن نہیں.چنانچہ
مفسرین نے کثرت سے یہ معنے بیان کیے ہیں.مشہور اوراہم شیعہ تفسیر بحارالانوار میں لکھا ہے:
”
اما قوله " إِلَّا مَاشَاءَ الله “ ففيه احتمالان - احدهما ان يقال هذه الاستثناء
غير حاصل في الحقيقة و أنه لم ينس بعد نزول“
(علامه مجلسی: بـجــار الانوار جزء ۱۷ صفحه ۹۷ باب ١٦ سهوه و نومه عن
الصلواة ایڈیشن ٤ مكتبه مؤسسة الوفاء بيروت لبنان ٥١٤٠٤ بمطابق (1983)
یعنی جہاں تک اللہ تعالیٰ کے اس قول " إِلَّا مَا شَاءَ اللہ “ کا تعلق ہے تو اس میں دو احتمال
پائے جاسکتے ہیں جن میں سے ایک یہ ہے کہ یہ در حقیقت استثناء غیر حاصل ہے.یعنی ایسا استثناء
کیا گیا ہے جو کبھی حقیقت میں ہوا ہی نہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم نزول قرآن کے
بعد کبھی متن قرآن میں سے کچھ نہیں بھولے اور تاریخ کی گواہی بھی اسی کے حق میں ہے.ایک دوسری جگہ علامہ مجلسی علامہ بیضاوی کا موقف بھی اپنے مؤقف کی تائید میں بیان کرتے ہیں :
Page 81
عہد نبوی میں جمع و تدوین قرآن
65
و قيل المراد به القلة أو نفى النسيان رأسا
(علامه مجلسی: بحار الانوار جزء ۱۸ صفحه ١٧٤ باب : ١، المبعث و اظهار الدعوه
و ما لقى...ایڈیشن ٤ مكتبه مؤسسة الوفاء بيروت لبنان ٥١٤٠٤ بمطابق 1983)
یعنی اس سے مراد قلت یا بھولنے کے بارہ میں ہر قسم کی نفی ہے.صاحب کشاف علامہ زمخشری نے اس آیت کی تفسیر میں یہی مضمون بیان فرماتے ہیں.حضرت امام رازی
آیت سَنُقْرِئُكَ فَلا تنسی کی تفسیر میں فرماتے ہیں:
یہ تو ایک بشارت الہی تھی جو آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی.خدا تعالیٰ آپ سے فرماتا
ہے کہ اے محمد ! میں تجھے ایسے حال میں رکھوں گا کہ تو اس قرآن کو بھول ہی نہ سکے گا.(تفسير كبير لامام رازى الجزء 31 تفسير سورة الاعلى: 7,8)
پس سَنُقْرِئُكَ فَلا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ الله (الاعلیٰ : 7,8) سے مراد ہے کہ اللہ تجھے پڑھائے گا اور اس کے
نتیجے میں تو ہر گز نہیں بھولے گا اور یہ خیال کہ بشری کمزوری کی وجہ سے انسان بھول سکتا ہے، بجا ہے لیکن ایسا ہوگا نہیں
کیونکہ جب کوئی کام خدا تعالیٰ کے زیر نگرانی اور اس کے ارادہ کے مطابق ہورہا ہو تو پھر وہ بشری کمزوریوں کو اپنے ارادہ
کے پورا کرنے کی راہ میں روک نہیں بنے دیتا.اس سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ وہ قراء تیں جو قرآن کریم کی اشاعت اور معارف و معانی کے سمجھنے کے لیے
وقتی طور پر ضروری ہیں وہ ضرورت پورا کرنے کے بعد بھلا دی جائیں گی.(حضرت حکیم مولوی نورالدین
صاحب) اس میں بھلا اعتراض کی گنجائش کہاں سے آگئی ؟ متن تو وہی رہے گا جو ہے اور جس کی محافظت قیامت
تک کے لیے ایک فیصلہ کن امر ہے.إِلَّا مَا شَاءَ اللہ کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ 'ہاں یہ ایسے ہوگا جیسے کہ اللہ چاہتا ہے.اور یہ قرآن مجید میں
واضح طور پر بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی حفاظت چاہتا ہے اور یہ کام اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے.چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:
إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ.(الحجر: 10 )
یعنی یقیناً ہم ہی نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں
اور یہ وعدہ بھی قرآن کریم میں ہی درج ہے کہ:
إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَ قُرْآنَهُ(القيامة : 18)
یعنی اس کا جمع کرنا اور اس کی تلاوت یقیناً ہمارے ہی ذمہ ہے.پس اللہ تعالیٰ نے اپنے اس وعدہ کے مطابق دُنیاوی لحاظ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حفاظت قرآن
Page 82
الذكر المحفوظ
66
کے لیے تمام ضروری سامان پورے کمال کے ساتھ مہیا کر دیے تھے اور صحابہ کی ایک ایسی جماعت عطا فرمائی تھی
جنہوں نے حفاظت قرآن اور اشاعت قرآن اپنی زندگیوں کا مقصد بنا رکھا تھا.جو قر آن کریم کی حفاظت کو ہر چیز
سے زیادہ عزیز سمجھتے تھے.پھر اس کے ساتھ ساتھ خدا تعالیٰ نے اپنی جناب سے بھی براہ راست حفاظت قرآن کی
غرض سے حیرت انگیز سامان فرمائے جو کہ انسانی طاقت اور قوت سے باہر تھے.مثلاً ہر رمضان میں جبرائیل کے
ساتھ قرآن کریم کی دہرائی اور آخری رمضان میں دو مرتبہ دہرائی (بخاریى كتاب فضائل القرآن باب كان جبريل
يـعــرض الـقــرآن على النبي ﷺ حفظ قرآن کا بے نظیر نظام اور ابتداء سے مسلمانوں کے دلوں میں قرآن کریم کا
والہانہ عشق اور محبت اور پھر حفاظت کا ایک یہ انتظام فرمایا کہ قرآن کریم کی زبان کو زندہ رکھا اور سنسکرت ، عبرانی
وغیرہ کی طرح مردہ نہیں ہونے دیا.صلى الله
عدوست
آنحضور ﷺ کی سعی مبارک
ایک طرف تو خدا تعالیٰ کی عدیم المثال حفاظت کے حصار میں قرآن کریم کی جمع کا کام ہورہا تھا اور پھر ظاہری
طور پر اس شان کے قومی آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب الہی سے عطا کیے گئے تھے.پھر نزول کی غیر معمولی طور
پر انتہائی کم رفتار، اور اس کے ساتھ ساتھ حفاظت کے دیگر غیر معمولی ذرائع اختیار کرنے کے باوجود آپ اپنی ذات
میں قرآن کریم کی حفاظت کے لیے کس قدر کوشاں رہتے تھے اس کا اندازہ اس آیت سے ہوتا ہے.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:
فَتَعلَى اللهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلُ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْل أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ
وَقُلْ رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا.(طه:115)
ترجمہ: پس اللہ ، مالک حقیقی بہت رفیع الشان ہے.پس قرآن (کے پڑھنے ) میں جلدی نہ
کیا کر پیشتر اس کے کہ اُس کی وحی تجھ پر مکمل کر دی جائے اور یہ کہا کر کہ اے میرے رب ! مجھے
علم میں بڑھا دے.چنانچہ روایات اور تاریخ میں اس بات کا کثرت سے ذکر ملتا ہے کہ جب آنحضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم پر کوئی آیت
نازل ہوتی تو آپ اسے یاد کرنے کے لیے تیزی کے ساتھ وحی الہی کے ساتھ ساتھ دہراتے تھے اس پر اللہ تعالیٰ
نے مذکورہ بالا حکم نازل فرمایا.پھر رسول کریم خود بھی کثرت سے تلاوت کیا کرتے تھے اور صحابہ کو بھی قرآن کریم سکھاتے تھے.چنانچہ اس
بارہ میں بھی قرآن کریم کی اندرونی گواہی ملتی ہے.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:
هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّنَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَتِهِ وَيُزَكِّيْهِمْ
Page 83
عہد نبوی میں جمع و تدوین قرآن
67
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَبَ وَالْحِكْمَةَ - (الجمعة : 3)
ترجمہ: وہی ہے جس نے اتمی لوگوں میں انہی میں سے ایک عظیم رسول مبعوث کیا.وہ اُن
پر اس کی آیات کی تلاوت کرتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب کی اور حکمت کی تعلیم
دیتا ہے جبکہ اس سے پہلے وہ یقینا کھلی کھلی گمراہی میں تھے.روایات میں بھی اس کا کثرت سے ذکر ملتا ہے.تلاوت قرآن اور تعلیم القرآن کے عناوین کے تحت کافی
تاریخی شواہد درج کیے جاچکے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرتے اور
درس و تدریس میں مشغول رہتے تھے.ذیل میں آپ کی تلاوت کے بارہ میں کچھ روایات درج کی جاتی ہیں.عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه و سلم قَالَ: مَا آذَنَ اللَّهُ
لِشَيْءٍ مَا أَذَنَ لِنَبِي حَسَنِ الصَّوْتِ يَتَغَنى بِالْقُرْآنِ يَجْهَرُ بِهِ ،
6
(سنن ابی داود کتاب الوتر باب استحباب الترتيل في القراءة)
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا
اللہ کسی چیز کو ایسی توجہ سے نہیں سنتا جس طرح قرآن کریم کو سنتا ہے جب کوئی پیغمبر اس کو خوش
الحانی سے بلند آواز سے پڑھے.“
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ : كَانَتْ قِرَاءَةُ النَّبي صلى الله عليه وسلم بِاللَّيْلِ
يَرْفَعُ طَوْرًا وَيَخْفِضُ طَوْرًا.“
66
(سنن ابی داود کتاب التطوع باب في رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل)
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ والہ وسلم رات کو کبھی بلند
آواز سے اور کبھی آہستہ آواز سے تلاوت کیا کرتے تھے.عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم
كَانَ يَقْرَأُ الْمُسَبْحَاتِ قَبْلَ أَنْ يُرْقَدَ يَقُولُ: إِنَّ فِيهِنَّ آيَةٌ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ آيَةٍ
الترمذي وابوداود بحواله مشكاة المصابيح كتاب فضائل القرآن
حضرت عرباض بن ساريه رضى الله عنه روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ و
الہ وسلم سونے سے قبل سُوَرُ الْمُسَبِّحات “ (سورۃ بنی اسرائیل ، سورۃ حدید سورۃ حشر سورۃ
صف ،سورۃ جمعہ ،سورہ تغابن اور سورۃ اعلیٰ) کی تلاوت فرمایا کرتے تھے.آپ فرماتے تھے کہ
ان میں ایک ایسی آیت ہے جو اپنے مضامین کے اعتبار سے ) ہزار آیات سے بڑھ کر ہے.عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم كَانَ لَا يَنَامُ حَتَّى
Page 84
الذكر المحفوظ
68
يَقْرَأْ أَلَمْ تَنْزِيل وَ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ.(احمد والترمذى والدارمى بحواله مشكاة المصابيح كتاب فضائل القرآن)
حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم سورۃ سجدہ اور
سورۃ ملک کی تلاوت کرنے سے پہلے نہ سوتے تھے.اور بھی بہت کثرت ایسی روایات ملتی ہیں کہ آنحضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم نا صرف یہ کہ خود کثرت سے تلاوت
کیا کرتے تھے بلکہ صحابہ سے بھی سنتے رہتے تھے.اسی طرح یہ بھی روایات ملتی ہیں کہ رسول کریم خود قرآن کریم
کی درس و تدریس میں مشغول رہا کرتے تھے.پھر یہ ذکر بھی گزر چکا ہے کہ تمام صحابہ اپنا حفظ اور اپنی تحریر
آنحضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی خدمت میں پیش کر کے اسے مستند بنایا کرتے تھے.پس جس شخص کا دن رات کا کام
تلاوت و تعلیم قرآن ہو وہ کس طرح بھول سکتا ہے.حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفتہ اسیح الثانی الصلح الموعود
رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:
ایک واقعہ کو کس طرح جھٹلایا جا سکتا ہے؟ جب واقعہ یہ ہے کہ قرآن کریم آپ
کو یا درہا اور
شب و روز نمازوں میں سُنا دیا جاتا رہا تو اس کا انکار کس طرح کیا جاسکتا ہے.محمد پر تو قرآن
اُترا تھا اور آپ کے سپر د ساری دُنیا کی اصلاح کا کام کیا گیا تھا.آپ اسے کیوں نہ یاد
رکھتے ؟ اور لاکھوں انسان موجود ہیں جنہیں سارے کا سارا قرآن یاد ہے.جب اتنے لوگ
اسے یاد کر سکتے تھے تو کیا وہی نہیں کر سکتا تھا جس پر قرآن نازل ہوتا تھا؟“
( فضائل القرآن ؛ انوار العلوم جلد 10 صفحہ 513)
صحامہ کی گواہی
صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایمان اور جانثاری اور قرآن کریم سے ان کی محبت اس بات کی گواہ ہے کہ وہ
اسے حرف بحرف کلام الہی سمجھتے تھے اور اتنے لمبے ساتھ اور زندگی کے ہزاروں چھوٹے بڑے مواقع پر آنحضور صلی
اللہ علیہ وسلم کے روز وشب کا گہری نظر سے مطالعہ کرنے کے بعد بھی اس بارہ میں کسی قسم کے شک میں مبتلا نہیں
ہوئے تھے.صحابہ کو کبھی یہ شکایت نہیں ہوئی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کوئی آیت بھول گئے اور آپ کو یاد
دلانی پڑی.ایک اور امر جس سے علم ہوتا ہے کہ صحابہ آنحضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کوسب سے مستند اور معتبر محافظ
قرآن یقین کرتے تھے یہ ہے کہ قرآن کریم کے بارہ میں چھوٹی سے چھوٹی بات کو بھی، جس سے اختلاف رائے
پیدا ہوتا ہو، رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے اور آپ کی رائے کو حتمی سمجھتے.چنانچہ تاریخ
کے اوراق میں بہت سے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ ادنیٰ سے اختلاف پر صحابہ نے کتاب اللہ کی غیرت اور محبت
Page 85
عہد نبوی میں جمع و تدوین قرآن
69
اور عشق میں انتہائی حساس طرز عمل دکھایا.یہاں تک کہ دیکھنے والے کو یقین ہو گیا کہ کلام الہی کے معاملہ میں ایک
دوسرے کی کوئی پروا نہیں کریں گے.مگر جب رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی خدمت میں معاملہ پیش ہوا تو
یکا یک ایسا محسوس ہوا کہ گویا کوئی اختلاف تھا ہی نہیں.صحابہ کا یہ طرز عمل بتاتا ہے کہ ان کو پورا یقین تھا کہ رسول
کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی سب سے بڑے مستند اور معتبر محافظ قرآن ہیں اور آج بھی امت مسلمہ کا یہی طرز عمل
ہے کہ کسی بھی اختلاف کی صورت میں قرآن کریم کے بعد آپ کے قول کو ہی تمام دوسرے اقوال پر حجت سمجھا جاتا ہے.بھولنا ایسے بھی ہوتا ہے کہ کوئی آیت مکمل طور پر بھول گئے ہوں اور ایسے بھی ہوتا ہے کہ پہلے ایک آیت ایک بار
پڑھی اور جب دوبارہ پڑھی تو الفاظ بھول گئے اور کچھ اور پڑھ لیے.مگر تاریخ کے صفحات ایسے واقعہ کی نشاندہی نہیں
کرتے کہ صحابہ کرام نے کبھی کوئی ایسی آیت پیش کی کہ یہ آیت پہلے پڑھی جاتی تھی مگر اے اللہ کے رسول صلی اللہ
علیہ والہ وسلم آپ اب اسے بھول گئے ہیں.بخاری اور دیگر کتب حدیث میں یہ جو روایت ملتی کہ کسی شخص کے
تلاوت کرنے پر آنحضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تیرا بھلا کرے تو نے مجھے یہ آیت یاد دلا دی.اس کا یہ
مطلب نہیں کہ فلاں آیت حافظہ سے اُتری ہوئی تھی.صرف یہ مراد ہے کہ جیسے عام روز مرہ کی بول چال میں کہا جاتا
ہے ” تمہاری اس بات سے مجھے فلاں بات یاد آ گئی.اس سے کہنے والے کی ہرگز مراد یہ نہیں ہوتی کہ وہ اب تک
بھولا ہوا تھا.مراد صرف اتنی ہوتی ہے کہ جو بات تم کر رہے ہو اس کا تعلق اس بات سے بھی ہے جو میں کرنے لگا
ہوں.مثلاً اگر کوئی کہے کہ ہسپتال سے یاد آیا کہ میرے والد صاحب بیمار ہیں.دعا کرنا.اب اس سے یہ مراد
نہیں ہوتا کہ کسی کو اپنے والد صاحب ہی بھول گئے تھے یا والد صاحب کی بیماری.مراد صرف اتنی ہے کہ ہسپتال کا
ذکر ہونے پر اسے اپنے والد صاحب کی موجودہ حالت کا خیال آگیا.مخالفین کی گواہی
پھر آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بھی آپ کر نازل ہونے والے کلام سے آشنا تھے.تبھی تو مخالفت کا بازار
گرم تھا.اگر آپ
کبھی بھولے ہوتے تو کوئی نہ کوئی ہمعصر مخالف ضرور کوئی مثال پیش کرتا کہ دیکھو پہلے محمد (ے)
نے یہ الہام پیش کیا تھا اور اب بھول گئے ہیں یا پہلے یہ آیت اس طرح تھی اب بھول کر بدل دی گئی ہے.پس اگر
ایسی بات ہوتی تو ان کے لیے موجب تسلی ہوتی کہ ہمیں اتنا سر ٹکرانے کی ضرورت نہیں یہ سلسلہ خود بخودہی اپنے منبع
سے دور ہوتے ہوتے اپنی اصلیت کھو دے گا.لیکن ایسا کبھی نہ ہوا.پس جب آپ تمیں سال نہیں بھولے اور تئیس سال کے بعد بھی آیات کو ویسے ہی پیش کرتے تھے جیسا کہ
پہلے دن پیش کی تھیں اور آپ کی قوم مخالف اور موافق گواہ ہیں، تو کیسے ممکن ہے کہ غیر معمولی حافظہ کے
حامل اور الوہیت کی چادر میں لیٹے ہوئے غیر معمولی صلاحیتوں کے مالک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزول کے
Page 86
الذكر المحفوظ
70
وقت کے معا بعد اس الہی امانت کو بنی نوع کے سپرد کرنے کے وقت تک جو کہ انتہائی مختصر ہوتا تھا کوئی آیت بھول
جاتے؟ یہ وقت تو بعض اوقات اتنا مختصر ہوتا کہ چند لمحات کا وقفہ ہوتا.محفل میں آیت نازل ہوئی اور اسی وقت
آپ نے اس الہی امانت کو ایک قوم کے سپرد کر دیا.ایک ایسی قوم کے سپر د کیا جس کے غیر معمولی حافظہ کے بارہ
میں کسی مؤرخ کو کلام نہیں.گزشتہ میں یہ ذکر بھی گزرچکا ہے کہ یہ بات ہمعصر مخالفین نے بھی نوٹ کی کہ قرآن
کریم فوری طور پر تحریری شکل میں محفوظ کر لیا جاتا ہے اور اس کا ذکر بھی کیا.قرآن کریم مخالفین کے اس اقرار کا ان
الفاظ میں ذکر کرتا ہے.وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْاَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا (الفرقان:6)
ترجمہ: اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو گزشتہ لوگوں کے قصے ہیں جو اس نے لکھوا لیے ہیں اور دن
رات اس کے سامنے ان کی املا کروائی جاتی ہے.واضح طور پر ذکر ہے کہ مخالفین کو علم تھا کہ دن رات قرآنی وحی کی تحریر کا کام ہوا کرتا تھا اور یہ بھی علم ہوا کہ خواہ
کسی بھی وقت وحی الہی نازل ہوتی تھی ، رات یا دن فوری طور پر ضبط تحریر میں لائی جاتی تھی.رات ہوتی تو دن کا
انتظار نہ کیا جاتا اور دن ہوتا تو رات کا انتظار نہ کیا جاتا.پس اس مختصر سے عرصہ میں کیسے غلطی ہو سکتی تھی؟
نیز یہ بھی سوچنا چاہیے کہ نزول کے وقت سے لے کر محفوظ کرنے کے وقت کے درمیان جو انتہائی کم عرصہ ہوتا
تھا اس معمولی عرصہ میں بھی اپنے کلام کی حفاظت کا ذمہ دار وہی خدا تھا جس نے بعد کے زمانوں میں اس کی
حفاظت کی.پس اگر بعد میں کوئی تبدیلی ثابت نہیں اور تمام ثبوت اس بات پر متفق ہیں کہ قرآن کریم میں کوئی
تبدیلی نہیں ہوئی تو پھر اس مختصر وقت میں وہ خدا کیوں حفاظت نہ کرتا جو پندرہ سو سال سے حفاظت کرتا چلا آ رہا ہے؟
پھرا بن وراق کہتا ہے کہ:
ہو سکتا ہے کہ صحابہ قرآن کا کوئی حصہ بھول گئے ہوں“
اس سوال کا بھی اتنا جواب ہی کافی ہے کہ اگر ایسا ہوا ہے تو ثبوت لاؤ.بلا ثبوت محض اندازے کون نہ
کرے گا.تمہارا شک غلط اور بے بنیاد ہے اور محض ایک حسرت ہے جو اندھے تعصب اور جہالت کا نتیجہ ہے.حقیقت یہ ہے کہ ایسا ہو نہیں سکا.قرآن کریم غیر ذمہ دار کھلنڈرے بچوں کے ہاتھ میں تو نہیں تھمایا گیا تھا کہ ہوسکتا
ہے یہ ہو گیا ہو ہو سکتا ہے وہ ہو گیا ہو.کلام الہی تو انتہائی ذمہ داری اور محبت کے ساتھ حفاظت کے تمام ممکنہ
تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اس طرح محفوظ کیا جارہا تھا کہ کسی قسم کی بھول چوک اور ایسی غلطی محال تھی جو اورں کی
نظروں میں آنے سے رہ جاتی.پہلے کتابت ہوتی پھر حفظ کیا جاتا.پس اگر اس امر محال
کو تسلیم بھی کر لیا جائے کہ
سینکڑوں صحابہ یکا یک کوئی آیت بھول گئے تو اس سے تو شور پڑ جانا چاہیے تھا.پھر اگر ایسا ہوا ہوتا تو کیا تحریرات
Page 87
عہد نبوی میں جمع و تدوین قرآن
71
وحی سے وہ آیت دوبارہ حفظ نہیں کی جاسکتی تھی ؟
اس اعتراض کا مفصل جواب تو گذشتہ صفحات میں درج جمع و تدوین قرآن کی تاریخ ہے.یہ ذہن میں رہے
که دنیوی مال و متاع جو انسان بہت محنت اور مشقت سے کماتا ہے اسے تو خاص حالات میں اپنی جان بچانے
کے لیے چھوڑ سکتا ہے.یا بڑے چاؤ سے تعمیر کرایا ہوا کوئی محل تو ممکن ہے کہ اپنی یا اپنے کسی پیارے کی جان کو
مشکل سے نکالنے کے لیے قربان کر دے.بہت آسانی سے جان کا صدقہ کہہ کر لوگ عمر بھر کی کمائی سے بھی منہ
موڑ لیتے ہیں لیکن اگر کسی چیز سے عشق کی حد تک محبت ہو جائے تو پھر اسے بڑی سے بڑی قیمت کے عوض بھی کھونا
گوارانہیں ہوتا.یہاں تک کہ جان کی قربانی بھی دینی پڑے تو انسان آسانی سے اس آزمائش سے گزر جاتا ہے
اور صحابہ کی ساری تاریخ گواہ ہے کہ ایک مرتبہ نہیں بلکہ بارہا انہیں موت کی آزمائش سے گزارا گیا مگر ہمیشہ وہ
کامیاب کامران ہوئے اور ہمیشہ انہوں نے جان کی قیمت دے کر اس الہی امانت کی حفاظت کی.حضرت عمرؓ کے
قبول اسلام کا واقعہ گزر چکا ہے.ان کی بہن جنہیں اپنے ایمان کی خاطر تشدد سے کچھ ہی دیر ہوئی تھی اور ابھی
زخموں سے خون جاری تھا، یہ کہہ کر اپنے بھائی حضرت عمر کو قرآن کریم کا مسودہ دینے سے انکار کر دیتی ہیں کہ تم
اسے چھو نہیں سکتے کیوں کہ تم نا پاک ہو.ذرا غور کیجیے کہ جس قوم کو قرآن کریم سے اس درجہ والہانہ عشق ہو کہ اُس
کی صنف نازک بھی اپنے لہولہو وجود کو قرآن کریم کی حفاظت کے لیے ڈھال بنا لیتی اور جس کو نا پاک سمجھتی اسے
چھونے بھی نہیں دیتی ، آنچ آنے دینا تو دور کی بات.کیا وہ قوم اتنی لا پرواہی کا ثبوت دے سکتی ہے جسکا دھڑ کا
ابن وراق کو لگا ہوا ہے؟ پس ایک طرف عشق اور محبت، ساتھ ساتھ انتہائی اعلی اخلاقی اقدار، اور دوسری طرف
احتیاط کے تمام دنیاوی تقاضے پورے کرنے کے بعد بھی اور اتنی واضح شہادتوں کے باوجود اگر تحریف ممکن ہے تو
پھر دنیا کی کون سی چیز ہے جو اصل سمجھی جائے گی ؟ کون سا ثبوت ہے جس کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے؟ اتنی واضح
شہادتیں موجود ہیں کہ رسول کریم حفاظت قرآن کا ایسا انتظام فرماتے تھے کہ بشری بھول چوک سے قرآن کریم کا
کوئی حصہ ضائع ہونا ناممکن ہے.ایک یا دو حافظ نہیں تھے کہ بھول گئے اور کسی کو علم ہی نہ ہوا اور کانتین میں سے کسی
نے بھی وہ آیت نہ لکھی ہو.کثرت سے صحابہ نزول کے ساتھ ساتھ قرآن کریم حفظ کرتے جارہے تھے.اور اس
کی باقاعدہ تلاوت کرتے رہتے تھے اور ان کی تعداد سینکڑوں بلکہ ہزاروں تک پہنچ رہی تھی.پس قرآن کریم کی
حفاظت تحریری اور حفظ دونوں طریق سے ہو رہی تھی.اور دونوں طریق بھی اپنی اپنی جگہ کمال کو پہنچے ہوئے تھے.اس صورت میں کیسے ممکن ہے کہ کسی وقت کوئی غلطی اتفاق سے متن میں راہ پا جائے اور وہی آیت اتفاق سے سب
حفاظ کو بھی بھول جائے.کوئی ایک غلطی کرتا تو دوسرا اسے یاد دلا دیتا اور یہ روایات بھی گزر چکی ہیں کہ ذرا ذرا سا
اختلاف اگر ہو جاتا تو فوراً رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے علم میں بات لائی جاتی.اتنی واضح اور قطعی شہادت
ہے کہ انتہائی درجہ نبی انسان ہی اس سے منہ پھیر سکتا ہے.یا پھر وہ جو دجل اور مکر میں حد سے گزر گیا ہو.آخر کس
Page 88
الذكر المحفوظ
72
طرح ممکن ہے کہ تحریر میں کوئی آیت رہ گئی ہو یا غلط لکھی گئی ہو اور رسول کریم کو علم نہ ہو؟ پھر سب حفاظ بھی اس آیت
کو بھول جائیں یا جو غلطی تحریر میں ہوئی ہے وہی غلطی یک بیک اور بالا تفاق سیکڑوں ہزاروں حفاظ کی یاداشت میں
بھی ہوگئی ہو؟ پھر رسول کریم کی یادداشت میں بھی وہی غلطی راہ پاگئی ہو جو حفاظ سے تلاوت سنتے رہتے تھے پھر بھی
آپ کو علم بھی نہ ہوا ہو اور پھر جبرائیل کے ساتھ قرآن کریم کے سالانہ دور میں بھی وہ غلطی درست نہ کی جائے؟
گویا خدا تعالیٰ کی نظر سے بھی رہ گئی.کیا ان تمام تاریخی ثبوتوں کی موجودگی میں یہ ماننا آسان ہے کہ قرآن کریم
محفوظ ہے یا وہم کو بنیاد بنا کر یہ وسوسہ پالنا کہ شائد کوئی غلطی ہوگئی ہو؟ ذرا ان تاریخی حقائق کو ذہن میں دہرائیں
کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم پر انتہائی معمولی رفتار سے قرآن کریم نازل ہورہا ہے اور ساتھ ساتھ آپ کی
نگرانی میں تحریر ہوتا جا رہا ہے اور آپ ہی کی نگرانی میں ساتھ کے ساتھ حفظ بھی ہو رہا ہے.نمازوں اور محافل میں
اس کی تلاوت ہوتی ہے.دن رات درس و تدریس بھی جاری ہے اور ایسے صحابہ موجود ہیں جو گویا قرآن کریم حفظ
کرنے اور اس کی تعلیم و تدریس کے لیے خود کو وقف کیے ہوئے ہیں اور صحابہ بھی ایسے جو قرآن کریم کی حفاظت
کے معاملہ میں اس درجہ غیرت مند ہیں کہ قرآن کریم کے بارہ میں کوئی ادنی سی لغزش بھی برداشت نہیں کرتے یا
لغزش نہ بھی ہومگر ان کے علم کے مطابق شک وشبہ والی بات ہو تو فوراً رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے فیصلہ
لے لیتے ہیں.پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم جبریل کے ساتھ ہر سال رمضان میں دہرائی کرتے ہیں.ان
حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے غور کیجیے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ ادھر حافظ بھولے ادھر وہی غلطی تحریر کرنے والوں سے بھی
ہوگئی اور پھر رسول کریم کی نظر سے بھی یہ بات اوجھل رہی ، جبرائیل بھی بھول گئے اور پھر جب حضرت ابوبکر کے
زمانہ میں جمع قرآن پر امت کو گواہ بنایا گیا تب بھی ساری امت اس غلطی پر متفق ہوگئی ؟ حضرت مرزا بشیر الدین
محمود احمد خلیفہ المسیح الثانی اصلح الموعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:.حضرت عمرؓ حضرت ابوبکر کے پاس گئے اور انہیں جا کر کہا کہ...قرآن کو ایک ہی جلد
میں جمع کر دینا چاہیے...جو کتاب گو ایک جلد میں اکٹھی نہیں کی گئی تھی لیکن بیسیوں صحابہ اسے
لکھا کرتے تھے اور ٹکڑوں کی صورت میں وہ لکھی ہوئی ساری کی ساری موجود تھی.اسے ایک جلد
میں جمع کرنے میں کسی کو دقت محسوس ہو سکتی تھی؟ اور پھر کیا ایسے شخص کو دقت ہوسکتی تھی جو خود
رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے زمانہ میں قرآن کی کتابت پر مقرر تھا اور اس کا حافظ تھا ؟ اور
جب کہ قرآن روزانہ پڑھا جاتا تھا، کیا یہ ہو سکتا تھا کہ اس جلد میں کوئی غلطی ہو جاتی اور باقی
حافظ اس کو پکڑ نہ لیتے ؟“
(دیباچہ تفسیر القرآن صفحہ 274 275)
پھر حفاظت کے ظاہری تقاضوں کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ خدا تعالیٰ کی تائید ونصرت اور اس کی حفاظت
Page 89
عہد نبوی میں جمع و تدوین قرآن
73
جو سب سے یقینی حفاظت ہے اس کلام کے شامل حال رہی.بلکہ قرآن کریم کی حفاظت کے تمام تر اقدامات خود
خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ہی تھے اور ہیں.اُس زمانہ کے حالات کو مد نظر رکھا جائے تو یہ حقیقت روشن تر ہو جاتی ہے
کہ حفاظت قرآن کے یہ اسباب میسر آجانا اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اس جانثاری کے ساتھ حفاظت
قرآن پر کمر بستہ ہو جانا بھی بذات خود الہی تائید کے لطیف اظہار ہیں.آخر کیوں یہ سب اسباب صرف حفاظت
قرآن کے لیے ہی اکٹھے ہوئے اور کیوں ایک قوم اس کتاب کی محبت میں عشق کی حد تک پہنچ گئی.کیا رسول کریم
پوری قوم اس طرح عاشق قرآن بنا سکتے تھے کہ وہ عشق پندرہ سو سال کے لمبے عرصہ پر محیط ہو جاتا اور ایک کے بعد
دوسری نسل اسی عشق میں سرشار نکلتی؟ آپ تو شائد اپنے ہمعصر لوگوں میں بھی یہ جذبہ اس شان کے ساتھ پیدانہ
کر سکتے جو کہ صدیوں سے امت محمدیہ کی زینت بن چلا آرہا ہے.حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب خلیفتہ اسیح الثانی اصلح الموعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:.اللہ تعالیٰ نے اسے ایسے عشاق عطا کئے جو اس کے ایک ایک لفظ کو حفظ کرتے اور رات دن
خود پڑھتے اور دوسروں کو سناتے تھے.اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے کسی نہ کسی حصے کا
نمازوں میں پڑھنا فرض مقرر کر دیا اور شرط لگادی کہ کتاب میں سے دیکھ کر نہیں بلکہ یاد سے
پڑھا جائے.اگر کوئی کہے کہ یہ محمد رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بات سوجھ گئی تھی تو ہم کہتے ہیں
کہ یہی بات زرتشت ، موسیٰ اور وید والوں کو کیوں نہ سو بھی.معلوم ہوتا ہے کہ اس کا سوجھانے والا
کوئی اور ہے.یہ بھی یادر ہے کہ ایسے آدمیوں کا میسر آنا جو اسے حفظ کرتے اور نمازوں میں
پڑھتے تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت میں نہ تھا.ان کا مہیا کرنا آپ کے اختیار سے
باہر تھا.اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ کہ ایسے لوگ ہم
پیدا کرتے رہیں گے جو اسے حفظ کریں گے.آج اس اعلان پر تیرہ سو سال ہوچکے ہیں اور قرآن
مجید کے کروڑوں حافظ گذر چکے ہیں.بعض یورپین ناواقفیت کی وجہ سے کہ دیا کرتے ہیں کہ اتنا
بڑا قر آن کس کو یا درہتا ہو گا ؟ مگر قادیان ہی میں کئی حافظ مل سکتے ہیں جنہیں اچھی طرح سے
قرآن یاد ہے.چنانچہ میرے بڑے لڑکے ناصر احمد سلمہ اللہ تعالیٰ نے بھی گیارہ سال کی عمر میں
قرآن کریم حفظ کر لیا تھا.( حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد تفسیر کبیر جلدم زیر تفسیر آیت الحجر :10)
پس ابن وراق ایسی معصومیت سے بات کر جاتا ہے کہ گویا کچھ علم ہے ہی نہیں کہ خدا تعالیٰ نے کس شان سے
حفاظت قرآن
کا انتظام کیا تھا.اس ضمن میں یہاں مزید ایک اور حیرت انگیز ثبوت پیش کر کے آگے بڑھتے ہیں.حفاظت قرآن کے ہی ضمن میں آنحضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے ایک حکم کی تعمیل میں آپ کے اقوال اور
Page 90
الذكر المحفوظ
74
احادیث عام طور پر تحریر نہ کی جاتی تھیں اور نہ ہی ان کے حفظ کا باقاعدہ انتظام تھا.صحابہ عشق رسول میں ڈوبے
ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے اقوال اور احادیث آپس میں سنتے سناتے.اس طرح آپ کے
اقوال سینہ بسینہ آگے منتقل ہوتے رہتے.قرآن کریم کے بارہ میں ہم دیکھ آئے ہیں کہ نزول کے ساتھ ساتھ
تحریری صورت میں محفوظ کیا جاتا اور اس کے حفظ کا باقاعدہ اہتمام کیا جاتا جس کے نگرانِ اعلیٰ خدا تعالیٰ کے بعد
خود رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم تھے اور پھر صحابہ کا کلام الہی سے عشق اور محبت اور اسکی غیرت بہت بڑے
نگران تھے.ان حقائق کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب اس واقعہ پر نظر ڈالیں کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ و
الہ وسلم نے شاہ مصر مقوقس کے نام ایک تبلیغی خط لکھا تھا.اُس خط کے الفاظ مسلمانوں نے آنحضور صلی اللہ علیہ والہ
وسلم سے سُن کر یا در کھے تھے جو کہ بعد میں تاریخ میں محفوظ کر لیے گئے.اب قریباً ایک سوسال قبل یہ خط اپنی اصل
صورت میں دریافت ہو چکا ہے.یہ 1858ء میں بعض فرانسیسی سیاحوں کو مصر کی ایک خانقاہ سے ملا اور اس وقت
قسطنطنیہ میں موجود ہے اور اس کا فوٹو بھی شائع ہو چکا ہے ( ریویو آف ریجنز قادیان اگست 1906 ء صفحه 364 )
اس خط کا دریافت کرنے والا مسیو استین برفیلمی تھا اور غالبا سب سے پہلے اس کا فوٹو مصر کے مشہور جریدہ الہلال
نومبر 1904ء میں شائع ہوا تھا اور پھر پروفیسر مارگولیتھ نے بھی اپنی کتاب محمد آئینڈ دی رائز آف اسلام میں اسے
شائع کیا.اسی طرح وہ مصر کی ایک جدید تصنیف تاریخ الاسلام السیاسی مصنفہ الدكتور حسن بن ابراہیم استاذ التاريخ
الاسلامی جامعہ مصریہ میں بھی چھپ چکا ہے اور بہت سے غیر مسلم محققین نے اس کی تصدیق کی ہے کہ یہ وہی اصل
خط ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے مقوقس شاہ مصر کو لکھا تھا.(حضرت مرزا بشیر احمد صاحب: سیرۃ خاتم
النبین حصہ سوم صفحہ 822) حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ دریافت شدہ اصل خط اور حافظہ کے دوش پر سو سال سے
زائد عرصہ کا سفر طے کر کے کتب حدیث میں جگہ پانے والا خط حیرت
انگیز طور پر لفظ لفظ ایک دوسرے سے ملتے ہیں.قابل غور بات یہ ہے کہ ایک خط کا زبانی روایات کی صورت میں ایک نسل سے دوسری نسل کو منتقل ہونا اور سو
دوسو سال کے بعد ان روایات کا تحریری شکل میں آنا اور پھر اس خط کا اصل حالت میں دریافت ہو جانا اور تاریخ
میں حافظہ کے ذریعے محفوظ کیے ہوئے خط اور دریافت ہونے والے اصل خط کی تحریر میں الفاظ تک میں مطابقت
ہونا یہ ثابت کرتا ہے کہ عربوں کا حافظہ کتنا مثالی اور غیر معمولی تھا اور یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ کس درجہ امانت دار تھی وہ
قوم کہ رسول
کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے پیغام کو جو اُن کے نام بھی نہیں تھا اس احتیاط سے حفظ کرتی تھی.پھر
کیسے ممکن ہے کہ اس پیغام کو جو رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا نہیں بلکہ خدا کا ہو، اور پھر ہو بھی بنی نوع انسان کی
ہدایت کے لیے، نیز سب سے پہلے مخاطب بھی صحابہؓ بنے ہوں اور پھر صحابہ اس کلام کی حفاظت کرنا اور اسے
بحفاظت بنی نوع کو منتقل کرنا اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی حفاظت کی تاکید
Page 91
عہد نبوی میں جمع و تدوین قرآن
75
فرماتے ہوں، اور پھر بھی صحابہ اس پیغام کی حفاظت سے غافل ہو جائیں ؟ پس اس شان کے حافظہ کے ساتھ اس
اعلیٰ درجہ کی امانت داری کے خلق کے حامل لوگ قرآن کو ایسی حالت میں حفظ کر رہے ہیں کہ انتہائی درجہ احساس
ذمہ داری بھی ہے اور دل میں والہانہ عشق بھی، اور پھر یہ پیغام تحریری صورت میں بھی موجود ہے اور رسول کریم صلی
اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثار صحابہ ہمہ وقت حفاظت اور نگرانی فرمارہے ہیں، تو دانستہ یا نادانستہ تبدیلی کس طرح
ممکن ہے؟ پھر یہ بھی دیکھیے کہ روایات تو اس کثرت سے سنائی نہ جاتی تھیں جس کثرت سے قرآن کریم کی درس و تدریس
اور تلاوت ہوتی تھی.پس قرآن کریم کا کوئی بھی حرف کسی بھی صورت میں بھول جاتا ، یہ بات بالکل ناممکن تھی.پھر اس پہلو سے بھی دیکھیے کہ مقوقس کے خط کے راوی چند ایک ہیں اور وہ خط صحابہ نے اپنے پاس تحریری
حالت میں بھی محفوظ نہیں کیا تھا اور سو سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا تھا جب یہ خط کتب احادیث میں درج کیا گیا.پھر بھی اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تو پھر قرآن کریم جو تحریری حالت میں موجود تھا اور تمام تر صحابہ جس کی صحت
پر گواہ تھے اور بلا مبالغہ سینکڑوں حفاظ موجود تھے اس میں کیسے کوئی بھول ہوسکتی ہے.اسی طرح یہ کہنا بھی جہالت کی حد ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کاتبین نے کوئی آیت غلط طور پر لکھ دی ہو.کتابت
قرآن کے بیان میں تفصیل سے درج کیا جاچکا ہے کہ کتابت کا انتظام بھی ایسا وسیع اور اعلیٰ درجہ کا تھا کہ کسی ایسی
بھول چوک کی گنجائش تھی ہی نہیں جو باقی صحابہ کی نظروں سے اوجھل رہ جائے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی
علم نہ ہو.پھر ہزاروں صحابہ کا حفظ کتابت پر نگران تھا دوبارہ انہی دلائل کو دہرا نا تکرار بے جا اور طوالت کا باعث
ہوگا.اختلاف مذہب کے باوجود اس بے نظیر حفاظت کے بارہ میں محققین گواہیاں دیتے آئے ہیں.ویلیم میور
بار بار مختلف الفاظ میں اس حقیقت کا اعتراف کرتا ہے.کہتا ہے:
"There is probably no other book in the world which
has remained twelve centuries with so pure a text"
(William Muir, Life of Mohamet, London, 1894, Vol.1,
Introduction)
قرآن کریم کے علاوہ) شائد دُنیا کے پردے پر اور کوئی ایسی کتاب نہیں جس کا متن بارہ
سوسال گزرنے کے باوجود اپنی اصل حالت میں قائم ہو.پھر لکھتا ہے:
"There is otherwise every security internal and
external that we possess the text which Muhammad
forth and used."
himself
gave
(William Muir, Life of Mohamet, London, 1894, Pg:561)
ترجمہ.اس کے علاوہ ہمارے پاس ہر ایک قسم کی ضمانت موجود ہے.اندرونی شہادت کی
Page 92
الذكر المحفوظ
76
بھی اور بیرونی کی بھی کہ یہ کتاب جو ہمارے پاس ہے، وہی ہے جو خود محمد ( صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم) نے دنیا کے سامنے پیش کی تھی اور اسے استعمال کیا کرتے تھے.Dr.Maurice Bucaille لکھتے ہیں:
They had the advantage of being checked by people
who already knew the text by heart, for they had learned
it at the time of the Revelation itself and had
subsequently recited it constantly.Since then, we know
that the text has been scrupulously preserved, It does
not give rise to any problems of authenticity.(The bible The Quran and Science (translation from French by
Alastair D.Pannel and The Ahthor)Under Heading Conclusions
Pg 250-251)
( جن لوگوں کو حضرت ابو بکر نے جمع قرآن کا حکم دیا تھا) انہیں یہ زائد فائدہ بھی حاصل تھا
کہ وہ (متن ) اُن لوگوں سے چیک کروالیا جاتا تھا جنہوں نے وحی کے نزول کے وقت ہی
اسے حفظ کرلیا تھا اور بار بار اس کی تلاوت کرتے رہتے تھے.اس وقت سے ، ہم جانتے ہیں کہ
قرآن کریم کا متن بلاشبہ محفوظ ہے اور اس کے استناد پر کوئی سوال نہیں اُٹھتا.اگر ادنی سا بھی شک ہوتا تو نامی گرامی محققین قرآن کریم کے بارہ میں یہ گواہی کیوں دیتے کہ روئے زمین پر
قرآن کریم ہی ایک ایسی کتاب ہے جس کے بارہ میں یقین سے کہا جاسکتا ہے کہ صدیوں کی اس دھوپ چھاؤں
نے اس میں کسی قسم کوئی رد و بدل نہیں دیکھا.قرآن کریم کا محفوظ ہونا تو آج ایک حقیقت بن چکی.اب مخالفوں کے سر پیٹنے سے یہ حقیقت نہیں بدل سکتی.آج اگر کوئی ان کے دھوکہ میں آ بھی گیا تو سوچنے کی بات ہے کہ قرآن کریم کی حفاظت پر اس سے کیا اثر پڑے گا.اس کے بعد ا بن وراق کہتا ہے : ” پھر ہمارے پاس شیطانی آیات کا قصہ ہے جو یہ بتاتا ہے
کہ محمد (ﷺ)
:.نے خود بھی کچھ آیات خرد برد کی ہیں.اس وسوسہ کا مفصل جواب قرآن کریم میں تحریف کے الزامات کے جواب
میں درج کریں گے.یہاں اتنا کہنا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ جس بنیاد پر تم یہ نتیجہ نکال رہے ہو اس کا جھوٹ اور
دجل تو گزشتہ سطور میں ظاہر ہو گیا.پس جب بنیاد ہی جھوٹی ہے تو نتیجہ کیسے درست مانا جاسکتا ہے.مضمون کی
ترتیب قائم رکھنے کے لیے جمع و تدوین قرآن کے دوسرے دور کے مطالعہ کا آغاز کرتے ہیں.
Page 93
عہد خلافت راشدہ میں جمع و تدوین قرآن
77
عہد خلافت راشدہ میں جمع و تدوین قرآن
گزشتہ سطور میں یہ ثابت ہو چکا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر نگرانی صرف انصار میں سے کم از کم
پانچ صحابہ تحریری طور پر مکمل قرآن کریم جمع کر چکے تھے.لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم
کے دور مبارک میں قرآن کریم ایک جلد میں کتابی صورت میں سامنے نہیں آیا تھا.بخاری کی اس روایت سے بھی
یہ حقیقت واضح ہوتی جس میں یہ ذکر ہے کہ جب حضرت عمرؓ نے حضرت ابوبکر کی خدمت میں جمع قرآن کی تجویز
پیش کی تو حضرت ابوبکر نے فرمایا:
كيف تفعل شياً لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم
شيألم
(بخاری کتاب فضائل القرآن باب جمع القرآن)
یعنی جو کام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟
اسی طرح حضرت زید بن ثابت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص کاتب وحی بھی تھے اور آپ کو
حضرت ابو بکر اور حضرت عثمان کے دور خلافت میں جمع قرآن کے سلسلہ میں بنیادی کردار ادا کرنے کی سعادت
ملی تھی، جب حضرت ابوبکر نے ایک جلد میں قرآن کریم جمع کرنے کا کام ان کے سپر د کیا تو اس موقعہ پر انہوں نے
وہی الفاظ کہے جو حضرت ابو بکر نے ارشاد فرمائے تھے کہ:
كيف تفعلون شيأ لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم
(بخاری کتاب فضائل القرآن باب جمع القرآن)
یعنی جو کام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ آپ لوگ کیسے کر سکتے ہیں؟
پھر انشراح صدر کے بعد پھر فرمایا کہ:
” میں نے مختلف جگہوں اور چیزوں سے قرآن کی آیات جمع کیں جو کھجور کی ٹہنی کے ڈنٹھل
66
اور پتھر کی باریک سلوں اور لوگوں کے سینوں میں محفوظ تھا.“
(بخاری کتاب فضائل القرآن باب جمع القرآن
اور فتح الباری میں حضرت زید رضی اللہ عنہ کی یہ روایت درج ہے کہ آنحضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی وفات
تک مکمل قرآن مجید کسی ایک جگہ جمع نہیں کیا گیا تھا.(فتح الباری جلد 9 صفحه 12 كتاب فضائل القرآن باب جمع القرآن)
مگر صحابہ حضرت زید اور بہت سے دیگر صحابہ کے پاس قرآن کریم مکمل طور پر تحریری صورت میں موجود تھا تو ایسی
روایات جن میں یہ ذکر ہے کہ ایک جگہ جمع نہیں تھا اُن میں ایک جگہ جمع کرنے سے یہی مراد ہو سکتی ہے کہ
Page 94
الذكر المحفوظ
78
قرآن کریم ایک جلد میں جمع نہیں تھا.چنانچہ روایات کا مطالعہ بھی یہی ثابت کرتا ہے.حضرت خلیفہ اسیح الثانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:.رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے زمانہ میں قرآن اس طرح ایک جلد میں نہ تھا جس
طرح اب ہے.حضرت عمرؓ کو یہ خیال پیدا ہوا کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ قرآن محفوظ نہیں.اس
لیے انہوں نے اس بارہ میں حضرت ابو بکر سے جو الفاظ کہے وہ یہ تھے کہ إِنِّي أَرَى أَنْ تَأْمُرَ
جَمْعَ الْقُرآنِ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ قرآن کو ایک کتاب کی شکل میں جمع کرنے کا حکم
دیں.یہ نہیں کہا کہ آپ اس کی کتابت کرا لیں.پھر حضرت ابوبکڑ نے زید کو بلا کر کہا کہ قرآن جمع
کرو.چنانچہ فرمایا جمعہ اسے ایک جگہ جمع کر دو یہ نہیں کہا اسے لکھ لو.غرض یہ الفاظ خود بتارہے
ہیں کہ اس وقت قرآن کے اوراق کو ایک جلد میں اکٹھا کرنے کا سوال
تھا لکھنے کا سوال نہ تھا.فضائل القرآن صفحہ 25 26 حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب خلیفہ اسیح الثانی
المصلح الموعودرضی اللہ عنہ )
سوال یہ ہے کہ جب اتنی جانفشانی سے حفاظت قرآن کا اہتمام کیا جا رہا تھا.اس کو تحریری شکل بھی دی
جاتی تھی ، اس کو ساتھ ساتھ حفظ بھی کیا جاتا تھا، اس کی درس و تدریس کا سلسلہ بھی جاری تھا، نمازوں میں اور
مجالس میں تلاوت بھی کی جاتی تھی، دن رات صحابہ اس کی درس و تدریس میں مشغول رہتے تھے، تو پھر کیوں
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک جلد میں اور کتابی شکل میں جمع نہیں کیا ؟
اس ضمن میں پہلے مختصر طور پر عرض ہے کہ جب تک وحی الہی مکمل نہیں ہو جاتی عملاً ایسا کرنا ناممکن تھا.کیونکہ
آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تک بقید حیات تھے تازہ بتازہ وحی کا نزول متوقع تھا اور اور ہمہ وقت انتظار کی سی کیفیت
ہوتی تھی کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے نئی آیات نازل ہوں.پس جب تک کہ یہ یقین نہ ہو جاتا کہ قرآن مجید کا
نزول مکمل ہو گیا ہے اُس وقت تک آخری حتمی شکل میں ایک کتاب کی صورت میں لکھا اور جمع کیا ہی نہیں جاسکتا
تھا.اور اس بات کا یقین صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی وفات سے ہی ہوا کہ قرآن کریم کا نزول مکمل
ہو گیا ہے کیونکہ اس کا نزول صرف آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی ذات بابرکات سے ہی خاص تھا.دوسری وجہ جس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کو ایک کتاب کی شکل میں پیش نہ کیا، یہ تھی کہ
قرآن کریم کی نزولی ترتیب اس کی دائی ترتیب سے مختلف تھی.ایسا نہیں تھا کہ جس ترتیب میں آیات نازل ہورہی
تھیں اسی ترتیب میں قرآن کریم میں مندرج ہوتی جا رہی تھیں.بلکہ بعد میں نازل ہونے والی آیات پہلے نازل
ہونے والی آیات سے پہلے بھی رکھی جاتی تھیں.یعنی بہت سی نئی نازل ہونے والی آیات ان آیات سے پہلے بھی رکھی
جاتیں جو کہ بہت پہلے نازل ہو چکی ہوتیں.ہر آیت کے نزول پر جبریل علیہ السلام آنحضور گو اس کی جگہ بتاتے تھے کہ
Page 95
عہد خلافت راشدہ میں جمع و تدوین قرآن
79
اسے فلاں سورت کی فلاں آیت سے پہلے یا بعد میں رکھا جائے یا یہ آیت کسی نئی سورت کی ہے جس کی ابتدا
ہو رہی ہے.پس ترتیب کے اس فرق کی وجہ سے بعد میں نازل ہونے والی وحی بطور ضمیمہ یا دوسری جلد کے
طور پر پیش نہیں کی جاسکتی تھی اس لیے یہ ناممکن تھا کہ جتنا ایک وقت تک نازل ہو چکا ہو اسے مجلد کتابی صورت
میں پیش کیا جا سکے.پس یہ محال تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قرآن کریم کو ایک مجلد کتاب کی شکل میں دُنیا
کے سامنے پیش کر دیا جاتا.گویا رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے دور مبارک میں جمع قرآن اور تدوین قرآن
کا فریضہ جہاں تک ممکن تھا مکمل طور پر سر انجام دیا جا چکا تھا اور جو ایک جلد میں جمع نہ کرنا تھا وہ بھی کسی کوتاہی پر
دلالت نہیں کرتا بلکہ ایک ناممکن العمل فعل تھا اس لیے نہ کیا گیا.خدا تعالیٰ نے یہ کام خلافت کی نگرانی میں صحابہ کے
ہاتھوں کرایا اور خلافت تو آتی ہی نبی کی خوبو پر ، نبی کے ہی کام کو جاری رکھنے اور آگے بڑھانے کے لیے ہے.اب جب کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی وفات کے بعد یہ بات واضح ہوگئی کہ وحی نبوت منقطع ہوگئی ہے
اور قرآن کریم کی مزید آیات نازل نہیں ہونگی کیونکہ ان کا نزول آنحضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی ذاتِ والا صفات
سے ہی خاص تھا اس لیے اب بہت ہی مناسب بات تھی کہ قرآن کریم کو ایک کتاب کی شکل میں اکٹھا کر لیا جائے.آنحضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے قرآن کریم کو ایک جلد کی شکل میں اکٹھا نہ کرنے کی حکمت کے بیان کے
ضمن میں ہی ایک اور بات کی مختصر وضاحت ضروری معلوم ہوتی ہے جو بعض علماء بلا سوچے سمجھے پیش کرتے ہیں.مثلاً الاتقان وغیرہ نے الخطابی کا یہ قول نقل کیا ہے.خطابی کا کہنا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے سارے قرآن کو ایک ہی جلد میں
اس لیے جمع نہیں کیا کہ آپ کو اس کی بعض آیات کے احکام یا ان کی تلاوت کے نسخ کے نزول
کا انتظار تھا.مگر جب آپ کی وفات سے قرآن کا سلسلہ ختم ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس
سچے وعدہ کو پورا کرنے کے لیے جو اس نے اُمت محمدیہ کی حفاظت کے متعلق فرمایا تھا خلفاء
راشدین کو الہام کیا کہ یہ کام کیا جائے.چنانچہ اس کام کا آغاز حضرت عمرؓ کے مشورہ سے
حضرت ابوبکر کے ہاتھوں ہوا.الاتقان فی علوم القرآن جزء اول صفحہ 85)
مندرجہ بالاسطور میں الخطابی کا یہ کہنا کہ بعض آیات کے نسخ نزول کا انتظار تھا، عجیب بات ہے.نسخ کے عقیدہ
پر بحث آئندہ سطور میں کی جائے گی یہاں یہ بحث اصل مضمون سے دور لے جائے گی.ہم صرف یہ پوچھتے ہیں
کہ یہ نتیجہ کہاں سے نکل آیا کہ نسخ کا انتظار تھا اس لیے مجلد کتاب کی شکل میں دینا ناممکن تھا؟ یہ خیال کیسے درست
Page 96
الذكر المحفوظ
80
مانا جاسکتا ہے کہ جو آیت بھی نازل ہوتی تھی وہ کسی نہ کسی آیت کو منسوخ ہی کرتی تھی ؟ اگر یہ کہا جائے کہ جب تک
آنحضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم حین حیات تھے، کسی ممکنہ وحی کا انتظار رہتا تھا تو کیا یہ کہنے سے بات مکمل نہیں
ہو جاتی ؟ ناسخ اور منسوخ کی یہاں کیا سوجھی.اپنی طرف سے حاشیوں پر حاشیے چڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ
کہنا ہی کافی ہے کہ قرآنی وحی کا نزول آنحضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی زندگی سے مشروط تھا.جب تک آنحضور
زندہ تھے یہ نہیں کہا جاسکتا تھا کہ اب قرآن کریم کی مزید وحی نہیں آئے گی.یہ بحث کرنا فضول ہے کہ اس وحی کی
شکل کیا ہوگی کیا نہ ہوگی؟ وہ ناسخ ہوگی یا منسوخ ہوگی؟ پس بلا دلیل اور بلاضرورت یہ کہہ دینا کہ نسخ کے نزول کا
انتظار تھا، زائد اور فضول بات ہے.یہ کہنا کافی ہے کہ مزید وحی کا نزول متوقع تھا.علامہ زرکشی فرماتے ہیں:
عہد رسالت میں قرآن کو ایک مصحف میں اس لیے نہ لکھا گیا تا کہ اس کو بار بار تبدیل
کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے.اس لیے قرآن کی یکجا کتابت کو اس وقت تک ملتوی رکھا گیا
جب تک کہ آنحضور کی وفات کی وجہ سے نزول قرآن کی تکمیل کا یقین نہیں ہو گیا.“
البرهان فی علوم القرآن جزء اول صفحه 262)
اس ضروری وضاحت کے بعد مضمون آگے بڑھاتے ہیں.حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں قرآن کریم کی خوب اشاعت ہو چکی تھی اور کثیر تعداد میں نسخے
موجود تھے.مسند خلافت پر متمکن ہونے کے ایک سال کے بعد حضرت عمر کی تجویز پر آپ نے حضرت زید بن
ثابت انصاری کو حکم دیا کہ وہ تحریری اور زبانی ہر دو قسم کی گواہی کے ساتھ قرآن کریم کو ایک مرکزی مجلد کتاب کی
شکل میں جمع کر دیں.چنانچہ احتیاط کے تمام تر تقاضے پورے کرتے ہوئے اور تمام امت مسلمہ کو گواہ بناتے
ہوئے حضرت ابو بکر کی سرکردگی میں اس کام کو بھی بخوبی سرانجام دیدیا گیا.اس سے پہلے مسلمہ طور پر چار صحابہ
کے پاس
مکمل لکھا ہوا موجود تھا جو کہ براہ راست آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں تحریر کیا گیا تھا اور منتشر طور پر
صحابہ کے پاس عام موجود تھا.ہزاروں حفاظ موجود تھے.دن رات درس و تدریس کے سلسلے جاری تھے.رمضان
میں مکمل قرآن کی تلاوت ہوتی تھی.نماز میں تلاوت، اجلاسات اور محافل میں تلاوت ہوتی تھی.حضرت عثمان
نے حضرت ابو بکر کے زیر نگرانی مدون ہونے والے نسخہ قرآن کریم کی نقول کروا کے مختلف صوبوں میں پھیلا دیں
اور پھر ان سے مزید نقول تیار ہوئیں.پس صحابہ کے دور میں جمع قرآن سے صرف یہ مراد ہے کہ قرآن کریم ایک کتابی شکل میں انتہائی احتیاط کے
ساتھ اکٹھا کر لیا گیا اور اس کی تعلیم وتفہیم اور اشاعت کا اعلیٰ انتظام کیا گیا.جمع قرآن صرف صحابہ کے دور سے ہی
Page 97
عہد خلافت راشدہ میں جمع و تدوین قرآن
81
خاص نہیں بلکہ جمع قرآن کی وہ شکل جو تعلیم واشاعت سے تعلق رکھتی ہے ہر دور میں امت مسلمہ کا فرض رہا ہے اور
یہ فرض ہمیشہ امت مسلمہ نے پوری تن دہی اور ایمانداری سے سرانجام دیا ہے اور آج بھی دے رہی ہے.آج بھی
قرآن کریم کی طباعت اسی احتیاط سے ہوتی ہے اور باقاعدہ حکومتوں سے منظور شدہ اہل علم قرآن کریم کی تحریر کا
گہری نظر سے جائزہ لیتے ہیں اور وہی قرآن کریم کا نسخہ مستند سمجھا جاتا ہے جس پر یہ گواہی درج ہو کہ یہ نسخہ مصحف
عثمان کے عین مطابق ہے.صحابہ کے دور میں جمع قرآن سے مراد اور اس کا محرک
یہ ثابت کیا جا چکا ہے کہ آنحضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی زندگی میں ہی قرآن کریم لکھا اور تحریری صورت
میں جمع اور محفوظ کیا جا چکا تھا اور اس کی مسلمانوں میں خوب اشاعت ہو چکی تھی.ہزاروں حفاظ موجود تھے.بہت
سے صحابہ کے پاس ذاتی تحریرات موجود تھیں جن میں قرآن کریم کی آیات درج تھیں.علامہ سیوٹی کا یہ بیان ہے
کہ امام ابن حزم نے لکھا ہے کہ خلیفہ اول کے دور میں کوئی شہر ایسا نہیں تھا جہاں لوگوں کے پاس بکثرت قرآن نہ
ہوں.رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے وصال کے بعد عرب میں ارتداد پھیلنا شروع ہوا اور جھوٹے مدعیان
نبوت بھی کھڑے ہو گئے.اسلام کے خلاف ہر قسم کی سازشیں ہونے لگیں اور بہت ہی پر آشوب دور تمام تر
ہولنا کیوں کے ساتھ اسلام کے سامنے آکھڑا ہوا.اسی دوران مسیلمہ کذاب سے ایک خونریز معرکہ ہوا جس میں
بہت کثرت سے حفاظ قرآن اور قراء صحابہ نے جام شہادت نوش کیا.اس خونریز معرکہ کی وجہ سے حضرت عمرؓ کے
دل میں ایک زبردست تحریک پیدا ہوئی کہ قرآن کریم کو تمام تر شبہات کے ازالہ کے ساتھ ایک جگہ لکھ کر جمع کر لیا
جائے ورنہ اگر اسی کثرت سے قراء و حفاظ صحابہ شہید ہوتے رہے تو قرآن کریم کا ایک حصہ کثیر ضائع ہو جائے گا.چنانچہ امام بخاری نے روایت کیا ہے:
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ حَدَّثَنَا ابْنُ
شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
قَالَ أَرْسَلَ إِلَيَّ أَبُو بَكْرٍ مَقْتَلَ أَهْلِ الْيَمَامَةِ فَإِذَا عُمَرُ بْنُ
الْخَطَّابِ عِنْدَهُ قَالَ أَبُو بَكْر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّ عُمَرَ أَتَانِي فَقَالَ
إِنَّ الْقَتْلَ قَدْ اسْتَحَرَّ يَوْمَ الْيَمَامَة بِقُرَّاء الْقُرْآنِ وَإِنِّي أَخْشَى أَنْ
يَسْتَحرَّ الْقَتْلُ بِالْقُرَّاءِ بِالْمَوَاطِن فَيَذْهَبَ كَثِيرٌ مِنْ الْقُرْآنِ وَإِنِّي
Page 98
الذكر المحفوظ
في
82
أَرَى أَنْ تَأْمُرَ بِجَمْع الْقُرْآنِ قُلْتُ لِعُمَرَ كَيْفَ تَفْعَلُ شَيْئًا لَمْ
يَفْعَلْهُ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عُمَرُ هَذَا وَاللَّهِ خَيْرٌ
فَلَمْ يَزَلْ عُمَرُ يُرَاجِعُنِي حَتَّى شَرَحَ اللَّهُ صَدْرِي لِذَلِكَ وَرَأَيْتُ
ذَلكَ الَّذِي رَأَى عُمَرُ قَالَ زَيْدٌ قَالَ أَبُو بَكْرِ إِنَّكَ رَجُلٌ
شَابٌ عَاقِلٌ لَا نَتَهِمُكَ وَقَدْ كُنْتَ تَكْتُبُ الْوَحْيَ لِرَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَتَبَّعْ الْقُرْآنَ فَاجْمَعْهُ فَوَاللَّهِ لَوْ كَلَّفُونِي
نَقلَ جَبَل مِنْ الْجِبَالِ مَا كَانَ أَثْقَلَ عَلَيَّ مِمَّا أَمَرَنِي بِهِ مِنْ جَمْعِ
الْقُرْآن قُلْتُ كَيْفَ تَفْعَلُونَ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هُوَ وَالله خَيْرٌ فَلَمْ يَزَلْ أَبُو بَكْرِ يُرَاجِعُنِي حَتَّى
شَرَحَ اللَّهُ صَدْرِي لِلَّذِي شَرَحَ لَهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُمَا فَتَتَبَّعْتُ الْقُرْآنَ أَجْمَعُهُ منْ الْعُسُب وَاللخَاف
وَصُدُورِ الرِّجَال
(بخاری کتاب فضائل القرآن باب جمع القرآن
عبید بن السباق سے روایت ہے کہ حضرت زید بن ثابت نے کہا کہ جنگ یمامہ کے شدید
خونریز معرکہ کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے مجھے بلا بھیجا.جب میں پہنچا تو حضرت عمرؓ بھی
وہاں موجود تھے.حضرت ابوبکر نے مجھ سے فرمایا کہ عمرؓ نے مجھ سے کہا ہے کہ یمامہ کے معرکہ
میں کثیر تعداد میں قراء قرآن کی شہادت کے واقعہ سے یہ ڈر پیدا ہوا ہے کہ اگر قراء کی شہادت
مختلف مقامات پر اسی طرح کثرت سے ہوتی رہی تو قرآن کا ایک کثیر حصہ ضائع ہو جائے گا.اس لیے میرا خیال ہے کہ آپ ( یعنی حضرت ابو بکر ) قرآن
کو جمع کرنے کا حکم دیں.(حضرت
ابوبکر فرمارہے ہیں کہ ) اس پر میں نے عمر سے کہا کہ جو کام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں
کیا وہ کام آپ کس طرح کر سکتے ہیں ؟ عمر نے کہا کہ خدا کی قسم اس کام میں بھلائی ہی ہے اور پھر
مجھ سے مسلسل اصرار کرتے چلے گئے حتی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس معاملہ میں انشراح صدر عطا
کیا اور میں بھی عمر کی رائے سے متفق ہو گیا.(حضرت ابو بکر حضرت زید سے مخاطب ہیں کہ )
آپ جوان اور دانا آدمی ہیں.آپ پر کسی نے کبھی الزام نہیں لگایا نیز آپ رسول اللہ صلی اللہ
Page 99
عہد خلافت راشدہ میں جمع و تدوین قرآن
83
علیہ وسلم کے کاتب وحی بھی تھے.اس لیے میرا خیال ہے کہ آپ ہی یہ کام کریں کہ قرآن کو تلاش
کریں اور سارے قرآن کو جمع کر دیں.حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ! اگر مجھے
کسی پہاڑ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کا حکم ہوتا تو وہ مجھ پر اتنا گراں نہ ہوتا جتنا کہ
قرآن کا کام مشکل تھا.اس پر میں نے حضرت ابوبکر سے کہا کہ آپ وہ کام کیونکر کریں گے جو خود
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تھا ؟ لیکن حضرت ابوبکر نے مجھے مسلسل اتنا سمجھایا کہ آخر خدا
نے مجھے بھی اس معاملہ میں شرح صدر عطا فرمایا جس بارہ میں حضرت ابوبکر و عمر کو شرح صدر عنایت
فرمایا تھا.تب میں نے مختلف جگہوں اور چیزوں سے قرآن کریم کو تلاش کیا جو کھجور کی ٹہنی کی ڈنٹھل اور
پتھر کی باریک سلوں اور لوگوں کے سینوں میں محفوظ تھا.اس روایت سے مندرجہ ذیل امور واضح ہوئے :
1 - قرآن کریم آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر نگرانی حفظ اور تحریر، ہر دو طور پر جمع اور محفوظ ہو چکا تھا.2.جنگ یمامہ میں قراء وحفاظ صحابہ کی کثرت سے شہادت اس جمع قرآن کا فوری اور بڑا محرک بنی.-3 جمع قرآن سے حضرت عمر کی مراد یہ تھی کہ قرآن کریم کو تحریری شکل میں ایک جگہ جمع کیا جائے مگر اس
مرتبہ کام کی نوعیت مختلف تھی.اس طرح تحریر کرنا تھا جس طرح اب سے پہلے کبھی ہوا نہیں تھا اور نہ ہی ہو سکتا تھا.مندرجہ بالا نتائج کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب اس سوال کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ جب قرآن کریم
تحریری شکل میں محفوظ تھا تو پھر کیوں حضرت عمرؓ کے دل میں حفاظ صحابہ کی شہادت سے قرآن کریم کے حصہ کثیر
کے ضائع ہونے کا خطرہ پیدا ہوا؟ اور پھر کافی لمبی بحث و تمحیص کے بعد حضرت
ابوبکر اور حضرت زید ، حضرت عمرؓ
سے متفق ہوئے.مختلف علماء جو یہ کہتے ہیں کہ حصہ کثیر سے مراد تحریرات کے کھو جانے کا خطرہ تھا، جیسا کہ الاتقان
اور البرھان میں یہ روایت ہے کہ اس بات کا خطرہ تھا کہ وہ اصل تحریرات وحی جو پہلی مرتبہ لکھی گئیں ان میں سے
کوئی حصہ کہیں ضائع نہ ہو جائے اور ضرورت تھی کہ قرآن کو اولین موقعہ پر ایک جگہ جمع کر لیا جائے (الاتقان فی
علوم القرآن جزء اول صفحه 60 / البرهان في علوم القرآن جزء اول صفحه (238) حضرت عمر کی روایت میں
تحریرات کے ضائع ہونے کے ڈر کا کہیں ذکر نہیں ہے.قرآن کے ضائع ہونے کا ذکر ہے اور کیا ایک نسخہ لکھ کر
جلد کروا لینے سے قرآن کریم محفوظ ہو جاتا؟ کیا آئندہ جب بھی 700 حفاظ شہید ہوتے تو ایک نسخہ ان کی جگہ لینے
کے لیے کافی ہوتا ؟ ذرا سا تجزیہ کرنے پر یہ بات بے وزن معلوم ہوتی ہے.حضرت ابوبکر کے دور میں جمع قرآن کے ضمن میں سب سے پہلے تو یہ مد نظر رہنا چاہیے کہ جب قرآن کریم
کثرت سے تحریری شکل میں موجود تھا تو حفاظ صحابہ کی وفات سے قرآن کریم کی تحریرات کے ضائع ہونے کا
Page 100
الذكر المحفوظ
84
کوئی ڈر نہیں ہوسکتا.یہ تو سوال دیگر جواب دیگر والی بات ہے.اگر ڈر ہوتا تو تحریرات کی بجائے حفاظ کی قلت کا
ڈر ہوتا.یہ تجویز دینی چاہیے تھی کہ قرآن کریم حفظ کرنے پر توجہ دی جائے اور کوئی مدرسۃ الحفظ قائم کیا جائے.کیونکہ تحریرات ضائع ہونے کا مسئلہ نہیں تھا حفاظ کی کثرت سے شہادت کا مسئلہ تھا اور قرآن کریم کی تحریرات
کے ضائع ہونے کا مسئلہ تو کبھی امت محمدیہ میں پڑا ہی نہیں.سوچنے والی بات ہے کہ 700 قراء شہید ہوئے اور
فکر یہ پڑ گئی کہ قرآن ضائع نہ ہو جائے اور پھر کام کیا کیا ؟ موجود نسخوں کو محفوظ کرنے کی بجائے اُن میں ایک اور
نسخہ کا اضافہ کر کے صحابہ مطمئن ہو کر بیٹھ گئے کہ اب قرآن محفوظ ہے.ذرا غور کریں کہ یہ بات تو انتہائی مضحکہ خیز
ہے.یہ ڈر محض ایک مجلد نسخہ کے اضافہ سے کیسے دُور ہو سکتا ہے.جہاں بیشمار تحریرات ضائع ہوسکتی ہیں کیا وہاں یہ
ایک نسخہ ضائع نہیں ہوسکتا ؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی اس واضح ہدایت کا ذکر گزر چکا ہے کہ آپ نے
جنگ میں قرآنی تحریرات ساتھ لے جانے کی ممانعت فرمائی تھی.اگر تحریرات کے ضائع ہونے کا ڈر تھا تو چاہیے
تھا کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی اس ہدایت کی اشاعت کی جاتی اور یہ حکم جاری کر دیا جاتا کہ
جنگ میں تحریرات قرآنیہ ساتھ نہ رکھی جائیں نیز کوئی بھی نیا نسخہ تحریر کرنے سے پہلے تو یہ چاہیے تھا کہ اُن پرانی
تحریرات کو محفوظ کرنے کے بارہ میں سوچتے جن کے ضائع ہونے کا خطرہ تھا اور اُن کو جلد کرواتے.انہی سوالات کے
جواب نہ پا کر آج کل کے بعض مسلمان علماء ان مستند روایات کا ہی انکار کر دیتے ہیں.مختصر یہ کہ حضرت عمرؓ کے ذہن
میں لازماً کوئی ایسی بات تھی جو تحریری صورت میں قرآن کو جمع کرنے کے علاوہ تھی اور وہ بات حفظ قرآن کی طرف توجہ
دلانا بھی نہیں تھی کیونکہ آپ نے کوئی مدرستہ الحفظ کھولنے کی تجویز نہیں دی.پھر حفظ قرآن کا کام بھی امت میں جاری
تھا.اگر چہ کافی تعداد میں حفاظ صحابہ شہید ہوئے تھے مگر اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ امت سے حافظ قرآن ہی ختم
ہوجائیں گے چنانچہ ہم صحیح بخاری کی اسی حدیث کی طرف لوٹتے ہیں جس میں جمع قرآن کے سلسلہ میں حضرت عمرؓ
کی تجویز کا ذکر ہے.اس حدیث میں اندورنی شہادت موجود ہے کہ حفاظت قرآن کے ضمن میں تحریری صورت میں
جمع کرنے کے علاوہ ایک اور بات حضرت عمر کے ذہن میں تھی جواب تک سرانجام نہیں دی گئی تھی.چنانچہ جب
حضرت عمرؓ نے یہ تجویز حضرت ابو بکر کے سامنے پیش کی تو حضرت ابو بکر نے حضرت عمرؓ کو یہ جواب دیا کہ:
میں نے (یعنی حضرت ابوبکر.ناقل ) نے عمر سے کہا کہ جو کام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے نہیں کیا وہ کام آپ کس طرح کر سکتے ہیں ؟ عمر نے کہا کہ خدا کی قسم اس کام میں بھلائی ہی
ہے اور پھر مجھ سے مسلسل اصرار کرتے چلے گئے حتی کہ خدا تعالیٰ نے مجھے اس بارہ میں انشراح صدر
عطا فر مایا اور میری بھی وہی رائے ہوگئی جو عمر کی تھی.اب دیکھا جائے تو تحریری شکل میں تو قرآن کریم کے بارہ میں بخاری اور صحاح ستہ کی واضح اور بہت کثرت
Page 101
عہد خلافت راشدہ میں جمع و تدوین قرآن
85
سے روایات موجود ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم قرآن کریم نزول کے ساتھ ساتھ تحریر کر وایا کرتے تھے
اور بخاری میں یہ واضح روایات بھی موجود ہیں کہ قرآن کریم مکمل طور پر تحریری شکل میں موجود تھا.مگر حضرت ابوبکر
فرمارہے ہیں کہ جو کام آنحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے نہیں کیا وہ کام ہم کس طرح کریں !؟ تحریری شکل
میں تو آنحضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم محفوظ کروایا کرتے تھے اور کیسے ممکن ہے کہ حضرت ابوبکر کو اس حقیقت کا
علم نہ تھا.علاوہ اور دلائل کے، خود اس روایت میں یہ شہادت موجود ہے کہ حضرت ابو بکر کو یہ علم تھا کہ رسول کریم
صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی وحی ضبط تحریر میں لائی جاتی رہی ہے.چنانچہ آپ کے یہ واضح الفاظ روایت میں درج ہیں کہ :
آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے کاتب وحی بھی تھے.اس لیے میرا خیال ہے کہ
آپ ہی یہ کام کریں.پھر حضرت زید کے علاوہ بھی صحابہ کے پاس کثرت سے قرآن کریم کی تحریرات موجود تھیں.کیسے ممکن ہے کہ
صحابہ میں اتنی کثرت سے قرآن کریم تحریر ہو رہا تھا مگر حضرت ابوبکر کو اس کا علم بھی نہ ہو.لازماً حضرت ابوبکر کے
اس فرمان کی حکمت پر غور کرنا پڑے گا.پھر اسی روایت میں ایک اور جگہ آپ حضرت زیڈ سے یہ فرماتے ہیں کہ :
"آپ ہی یہ کام کریں کہ مختلف چیزوں پر لکھے ہوئے حصہ ہائے قرآن کو تلاش کریں اور
سارے قرآن کو ایک جگہ جمع کر دیں
پھر یہ کہ اگر صرف قرآن کریم کو تحریری شکل میں جمع کرنا ہی مقصد تھا تو پھر اس صورت میں یہ بھی ماننا پڑے گا
کہ حضرت عمر کو بھی یہ علم نہیں تھا کہ قرآن کریم تحریری صورت میں محفوظ ہو چکا ہے اور یہ بھی ناممکن اور محال ہے.پس لازماً کوئی ایسا کام پیش نظر تھا جو حضرت رسول کریم نے نہیں کیا تھا اور صحابہ کی شہادت سے اس کام کا پورا کرنا
مشکل تر ہوتا جارہا تھا اور وہ صرف تحریری شکل میں جمع کرنے کا کام نہیں ہوسکتا تھا کیونکہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
اپنی نگرانی میں کر چکے تھے.اگر کہا جائے کہ ایک جلد میں تحریر کرنا تھا تو یہ کوئی ایسی بات تو نہیں کہ حضرت ابوبکر اور
حضرت زید رضی اللہ عنہما اتنا پس و پیش کرتے اور اتنی بے چینی کا اظہار کرتے.حضرت زیڈ کے پس و پیش کا
مطلب تو بالکل سمجھ نہیں آتا کیونکہ آپ تو پہلے بھی تو لکھ چکے تھے.پس اس حق میں کہ صرف تحریری شکل میں ایک
جلد میں جمع کرنا ہی مقصود نہیں تھا ایک بہت مضبوط دلیل اسی روایت سے ملتی ہے اور وہ حضرت زید کا یہ قول ہے کہ:
خدا کی قسم ! اگر مجھے کسی پہاڑ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کا حکم ہوتا تو وہ مجھ پر اتنا
گراں نہ ہوتا جتنا کہ قرآن کا کام مشکل تھا.اس پر میں نے حضرت ابوبکر سے کہا کہ آپ وہ کام کیونکر
کریں گے جو خو د رسول
اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے نہیں کیا تھا؟“
کتابت قرآن کا کام تو حضرت زید پہلے بھی کرتے رہے تھے، کیا صرف نیا نسخہ تحریر کروانا آپ کو پہاڑ جیسا
Page 102
الذكر المحفوظ
86
مشکل لگا؟ نیز کیا قرآن کریم کی تحریرات کو جلد کروانا پہاڑ کو دوسری جگہ منتقل جتنا مشکل تھا؟ پس مجلد شکل میں پیش
کرنا تھا مگر اس طرح کہ یہ کام پہاڑ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے سے زیادہ مشکل ہو گیا تھا.اگر ایسا نہیں
تھا تو حضرت زید کو تو کہنا چاہیے تھا کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں میرے پاس اور دوسرے صحابہ کے پاس پہلے سے
ہی قرآن کریم تحریری طور پر محفوظ ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں تیار کیا گیا ہے.انہی تحریرات کو
جلد کر لیتے ہیں یا اُن کی نقل تیار کر کے جلد کر لیتے ہیں.پھر آئندہ جو لائحہ عمل بنایا گیا اور جو کام کیا گیا وہ بھی یہی
بتاتا ہے کہ مقصد صرف ایک مجلد نسخہ کی تیاری نہیں تھا.المختصر حضرت عمرؓ کی طرف سے ایک ایسی تجویز پیش کی گئی تھی
جو اپنی ذات میں بالکل نئی تھی اور یہ کام پہلے کبھی نہیں ہوا تھا اور وہ کام تھا بھی بہت عظیم الشان اور بقول حضرت زید
پہاڑ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے سے زیادہ مشکل تھا تحریر کروانا اتنا مشکل کیونکر ہوگیا؟ پھر حضرت زید تو نسخہ کی تیاری
کو مشکل قرار دے رہے ہیں تحریر کر وانے یا جلد کروانے کو نہیں چنانچہ نسخہ تیار کرنے کے بعد جلد کرنے کا ذکر بھی نہیں کرتے.پس نسخہ تحریر کروانا یا تحریرات جلد کروانا بہر حال پہاڑ ڈھونے جتنا مشکل نہیں ہوسکتا.اور اس امر کی کہ تحریرات
میں کمی کا اندیشہ نہیں تھا ایک اور بھی دلیل ہے کہ جب حضرت عمر کی تجویز کے مطابق نسخہ تیار ہو گیا تو تاریخ میں
ذکر نہیں ملتا کہ صحابہ اس نسخہ کی نقلیں کروانے ٹوٹ پڑے ہوں.پس تحریرات کافی وشافی موجود تھیں.مختصر یہ کہ یہ تو واضح ہے کہ مسئلہ حفاظت قرآن کا ہی در پیش تھا اور کوئی نہیں تھا اور یہ بھی واضح ہے کہ حفاظ کی
تعداد کم ہونے یا تحریرات کے کم ہونے کا اندیشہ نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ حضرت عمرؓ کے نزدیک اس مسئلہ کا حل نہ تو
حفاظ کی تیاری میں تھا اور نہ ہی آپ اس وقت قرآن کریم کی کثرت سے تحریری اشاعت کی تجویز دے رہے
تھے.بلکہ جو مسئلہ تھا وہ ایک مخصوص نسخے کی تیاری کا تھا جو کہ اب تک تیار نہیں ہو ا تھا.اور اُس نسخہ کی تیاری پہاڑ
جیسا مشکل کام تھا نہ کہ اس
کوتحریر کرنا یا اس کو جلد کرنا.ایک اور بات واضح ہے کہ اس تجویز کا تعلق صحابہ کی شہادت
سے تھا.صرف صحابہ کی موجودگی میں ہی یہ کام ہوسکتا تھا صحابہ کے بعد نہیں نیز تھا بھی بہت اہم اور مشکل.ذیل کی سطور میں ہم ان سوالات کے جوابات تلاش کریں گے کہ اگر صرف کتابی شکل میں ہی پیش کرنا مقصود
تھا تو پھر حفاظ کی شہادت سے قرآن کے ایک بڑے حصہ کے ضائع ہونے کے کیا معنی ہوں گے؟ حضرت ابوبکر
اور پھر حضرت زیڈ کے اس قول کا کیا مطلب ہے کہ ”جو کام رسول کریم نے نہیں کیا وہ ہم کیسے کریں؟ نیز حضرت
زیڈ کے اس قول سے کیا مراد ہے کہ یہ کام مجھے کسی پہاڑ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے سے زیادہ دشوار
لگا؟ یہ سوالات اسی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ صرف کتابی شکل میں پیش نہیں کیا گیا تھا بلکہ کچھ گہرا کام کیا گیا تھا
جو رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے زمانہ میں کرنا ممکن نہیں تھا.لیکن اس نسخہ میں ایسی خاص بات کیا تھی ؟ ان
سوالات پر نظر ڈالنے کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ عصر حاضر میں مستشرقین بہت کثرت سے یہ سوالات
Page 103
عہد خلافت راشدہ میں جمع و تدوین قرآن
87
اُٹھاتے ہیں اور بہت سے مسلمان علماء اِن سوالات سے نظریں چراتے ہیں اور بعض تو جواب نہ ملنے کی وجہ سے
حضرت
ابوبکر کے اس عظیم الشان کارنامہ کو تسلیم کرنے سے ہی انکار کر دیتے ہیں.حضرت ابوبکرؓ کے عہد خلافت میں جمع قرآن کا طریق
مستند روایات کے مطابق حضرت ابوبکر، حضرت عمرؓ کے مشورہ پر جمع قرآن کے لیے رضامند ہو گئے اور پھر
اس بنا پر کہ حضرت زید بن ثابت ایک بے داغ کردار کے حامل ، جوان ، ذہین اور پڑھے لکھے صحابی تھے اور سب
سے بڑھ کر یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے اُن معتبر صحابہ میں سے تھے جنہیں حضرت رسول خدا نے وحی الہی
لکھنے کی ذمہ داری سونپی ہوئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی نگرانی میں قرآن
کریم تحریر فرماتے تھے.اسی
سعادت کی وجہ سے حضرت ابوبکر نے بھی آپ ہی کے ذمہ یہ کام لگایا کہ آپ قرآن کریم کو جمع کریں.مکمل
انشراح صدر کے بعد حضرت زید نے اس کام کا بیڑا اٹھایا.آپ فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن کریم تحریر اور حفاظ
کی گواہیوں کے ساتھ جمع کیا.(بخاری کتاب فضائل القرآن باب جمع القرآن)
مندرجہ بالا وضاحت کے بعد اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ وہ کون سا انوکھا اور بھاری کام تھا جس پر حضرت ابو بکر
اور حضرت زید اتنی سوچ و بچار کے بعد راضی ہوئے تھے.بعد کے حالات کے تفصیلی مطالعہ سے واضح ہو جاتا ہے
کہ تحریری صورت میں موجود ہونے کے بعد جمع قرآن کس طرز پر ہوا اور اس میں کیا حکمت پوشیدہ تھی ؟ آئیے اُن
احادیث کا دوبارہ جائزہ لیتے ہیں جن سے حضرت زید کے طرز عمل کا پتہ ملتا ہے.حضرت زید فرماتے ہیں:
تب میں نے مختلف جگہوں اور چیزوں سے قرآن کریم کو تلاش کیا جو کھجور کی ٹہنی کی ڈنٹھل اور
پتھر کی باریک سلوں اور لوگوں کے سینوں میں محفوظ تھا.(بخاری کتاب فضائل القرآن باب جمع القرآن)
اس طریقہ کار کی وضاحت کرتے ہوئے علامہ سیوطی فرماتے ہیں :
ان ابا بكر قال لعمر و لزيد اقعدا على باب المسجد فمن جاء كما
بشاهدين على شيء من كتاب الله فاكتباه
(الاتقان في علوم القرآن جزء اول النوع الثامن عشر في جمعه و ترتیبه صفحه 58)
جب جمع قرآن کا فیصلہ ہو گیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر اور
حضرت زید (رضی اللہ عنہما) کو حکم دیا کہ مسجد کے دروازہ پر بیٹھ جائیں اور جو کتاب اللہ کا کوئی
حصہ دو گواہوں کے ساتھ لائے وہ حصہ لکھ لیں.قـدم عـمـر فـقـال مـن كـان تلقى من رسول الله لا شيئا من القرآن فليأت
Page 104
88
الذكر المحفوظ
به....وكان لا يقبل من احد شيئا حتى يشهد شهيدان و هذا يدل على ان
زيدا كان لا يكتفى بمجرد وجد انه مكتوبا حتى يشهد به من تلقاه سماعا
مع كون زيد كان يحفظ فكان يفعل ذلك مبالغة في الاحتياط...و كان
الناس يأتون زيد بن ثابت فكان لا يكتب آية الا بشاهدى عدل.(الاتقان في علوم القرآن جزء اول النوع الثامن عشر في جمعه و ترتیبه صفحه 58)
چنانچہ حضرت عمر نے اعلان فرمایا کہ جس کسی کے پاس آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا ہوا یا لکھا
ہوا کوئی حصہ قرآن ہو تو لے آئے اور وہ اس وقت تک کوئی آیت قبول نہیں کرتے تھے جب تک دو
قسم کی شہادتیں نہ اکٹھی ہو جاتیں.زید صرف تحریر پر اکتفا نہیں کرتے تھے اور حفظ کی گواہی بھی طلب
کرتے تھے.حضرت زید خود بھی حافظ قرآن تھے لیکن اس کے باوجود بدرجہ کمال احتیاط کے تقاضے
پورے کرتے ہوئے حفظ کی گواہی بھی لیتے تھے.لوگ حضرت زید بن ثابت کے پاس اس اعلان
کے موافق آتے تھے.مگر وہ کوئی ایک آیت بھی بغیر دوعا دل گواہوں کی گواہی کے نہیں لکھتے تھے.(الاتقان فی علوم القرآن جزء اول النوع الثامن عشر في جمعه و ترتیبه صفحه 58)
اس سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت عمر اور حضرت زید مختلف صحابہ کے پاس موجود تحریر شدہ قرآن کریم پر ہی اکتفا
نہیں کر رہے تھے بلکہ خود حافظ قرآن ہونے کے باوجود تحریرات وحی بھی طلب کرتے اور حفاظ صحابہ کی گواہی بھی
لیتے.اس طرح حضرت زید حفظ اور تحریر، دونوں قسم کی کم از کم دو دو شہادتیں حاصل کرنے کے بعد ہر آیت احاطہ تحریر
میں لاتے.قرآن کریم کو اس طرح تحریر کرنے میں ایک تو حد درجہ احتیاط کا پہلو کارفرما تھا اور دوسرے اس سے
قرآن کریم کی ایک ایسی عظیم الشان مصدقہ خدمت تھی جو اس سے قبل کسی کتاب
کی نہ کی گئی تھی.دو گواہیوں سے مراد تعداد کے لحاظ سے دو گواہیاں نہیں تھیں بلکہ دوستم کی گواہیاں تھیں.ایک گواہی یہ لانی
ہوتی تھی کہ کم از کم دو حفاظ ہوں جنہوں نے آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حفظ کیا ہو یا آپ کے حضور اپنا حفظ پیش
کر کے تصدیق کر والی ہو اور دوسری قسم کی گواہی یہ تھی کہ آیت کی کم از کم دو تحریرات پیش کی جائیں جو کہ بعد از تحریر
آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چیک کروا کر مستند بنالی گئی ہوں.اس طرح ہر آیت پر کم از کم چار گواہیاں اکٹھی کی
جاتیں کہ یہ آیت بعینہ وہی ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا ئی تھی.چنانچہ علامہ سیوطی فرماتے ہیں:
قال ابن الحجر وكان المراد بالشاهدين الحفظ و الكتاب.و قال
السخاوي في جمال القراء المراد انهما يشهدان على ان ذلك
المكتوب كتب بين يدى رسول الله ﷺ او المراد انهما يشهدان على
ان ذالك من الوجوه التي نزل بها القرآن قال ابوشامة و كان عرضهم
Page 105
عہد خلافت راشدہ میں جمع و تدوین قرآن
89
ان لا يكتب الا من عين ما كتب بين يدى النبي ﷺ لا مجردا لحفظ
(الاتقان في علوم القرآن جزء اول النوع الثامن عشر في جمعه و ترتيبه صفحه (58)
ابن حجر کا قول ہے کہ دو گواہوں سے مراد حفظ اور کتابت تھی اور سخاوی نے اپنی کتاب جمال
القراء میں لکھا ہے کہ اس سے یہ مراد ہے کہ دو گواہ اس بات پر گواہی دیں کہ وہ لکھا ہوا قرآن
خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے روبرو لکھا گیا ہے...ابو شامہ کا قول ہے کہ ان صحابہ
کی غرض یہ تھی کہ قرآن اُسی اصل سے تحریر میں لایا جائے جو اصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
حیات مبارکہ میں آپ
کی نگرانی میں تحریر میں آیا ہے نہ کہ محض حافظہ پر اعتماد کر کے لکھ لیا جائے.ڈاکٹر صبحی صالح لکھتے ہیں:
"جمہور کے نزدیک دو عادل گواہ حفظ کے لیے اور دو کتابت کے لیے یعنی کل چار گواہ ضروری تھے.“
( علوم القرآن ، 1993 : باب دوم فصل اول عہد عثمان میں جمع تدوین صفحہ 111)
اب یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اگر قرآن کریم کو محض تحریری صورت میں ایک جلد میں جمع کرنا مقصود تھا
تو کیوں نہ دو چار ، دس ہیں حفاظ کو بٹھا لیا گیا اور قرآن کریم کو بجائے اٹھارہ مہینوں کے لمبے دور کے فوری طور پر
تحریر کر لیا گیا؟ پس محض حافظہ پر انحصار نہ کیا گیا.علاوہ ازیں یہ بھی ممکن تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے
زیر نگرانی تحریر کیے گئے نسخوں سے ایک اور نسخہ تیار کر لیا جاتا لیکن ایسا بھی نہ کیا گیا.مقصود یہ تھا کہ قرآن کریم کو آخری
کتابی شکل میں محفوظ کر دیا جائے.پھر کیوں بظاہر آسان راہوں کو چھوڑ کر وہ راہ اختیار کی گئی جو مشکل تر تھی ؟
اس کا جواب یہ ہے کہ اس آخری شکل میں محفوظ کرنے کے لیے بہترین طریقہ یہ تھا کہ امت محمدیہ کی گواہی
ساتھ شامل ہو جائے اور وہ طریقہ اختیار کیا جائے جس پر امت مسلمہ میں کوئی بے چینی راہ نہ پائے اور اب تک
آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم حفاظت قرآن کے ضمن میں جس جانفشانی اور اکمال کے ساتھ کام سرانجام دے چکے تھے
اس میں کسی قسم کا شک نہ رہے اور آئندہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قرآن
کریم کو مکمل
طور پر شک وشبہ سے بالا کر کے پیش کیا مگر صحابہ کے دور میں کوئی تبدیلی راہ پاگئی.اگر چند صحابہ ان نسخوں سے مزید
نقول تیار کرتے تو شک پیدا ہو سکتا تھا کہ گنتی کے چند صحابہ نے ہی تو قرآن آگے پہنچایا ہے اور اس چھوٹے سے
گروہ سے غلطی ہو جانا قرین قیاس تھا یا اس قلیل تعداد کا کسی بددیانتی پر اکٹھے ہو جانا شائد ایک عام دنیا دار کی آنکھ
میں ممکن العمل ہوتا.اگر چہ صحابہ کی تاریخ اور ان کے مناقب کا مطالعہ یہ ادنی سا بے دلیل شبہ بھی باقی نہیں رہنے
دیتا کیونکہ یہ لوگ تو ہر طرح سے آزمائے جاچکے تھے.علاوہ دوسرے پہلوؤں کے اس پر بھی غور کیجیے کہ جولوگ
اس درجہ محتاط ہیں کہ ایک کام جس میں سراسر خیر ہے اس کے کرنے سے اس لیے گھبراتے ہیں کہ یہ کام رسول کریم
نے نہیں کیا تو ہم کس طرح کر لیں.کیسے ممکن ہے کہ یہ لوگ کسی بھی قسم کی تحریف کے مرتکب ہو جائیں؟ لیکن پھر
Page 106
الذكر المحفوظ
90
بھی بدطینت لوگ جو دیانت داری کی پروا کیے بغیر صرف اسلام دشمنی میں اعتراض برائے اعتراض کرتے چلے
جاتے ہیں اُن کو یہ کہنے کا ایک موقعہ مل جاتا کہ قرآن کریم کی حفاظت میں شبہ ہے کیونکہ یہ چند صحابہ کے ہاتھوں
سے ہو کر ہم تک پہنچا ہے.ہو سکتا ہے ان چند صحابہ نے کسی وجہ سے کوئی تحریف کر دی ہو یا اس قلیل جماعت سے
کوئی غلطی ہوگئی ہو.چنانچہ اس طریقہ کار سے ممکنہ شک کا بھی قلع قمع ہو جاتا ہے کیونکہ ساری قوم کا اس طرح
جھوٹ پر اکٹھا ہو جانا یا مجموع طور پر سی غلطی کا شکار ہوجانا ناممکن ہے.حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب خلیفہ اسیح الثانی اصلح الموعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں :
کوئی سورۃ نہیں لکھی گئی کوئی آیت نہیں لکھی گئی کوئی زیر اور زیر نہیں لکھی گئی جس کے متعلق
دو قسم کی شہادتیں نہیں لی گئیں.ایک یہ کہ تحریر موجود ہو، دوسرے یہ کہ زبانی گواہ موجود ہوں جو یہ
کہتے ہوں کہ ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا نا ہے.یہ
کتنی بڑی محنت ہے اور کتنی
بڑی احتیاط کا ثبوت ہے.زبانی گواہی کو نہیں مانا گیا جب تک اُس کے ساتھ تحریری شہادت نہ
ہو اور تحریری شہادت کو نہیں مانا گیا جب تک اُس کے ساتھ زبانی گواہ نہ ہوں.گویا تحریر بھی موجود
ہو اور زبانی گواہ بھی موجود ہوں تب کسی سورۃ یا آیت کو قرآن کریم میں شامل کیا جاتا اور یہ زبانی
گواہ بھی بعض دفعہ سینکڑوں تک ہوا کرتے تھے صرف ایک دو آیتیں ایسی ہیں جن کے متعلق
صرف دو دو گواہ ایسے ملے ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم
سے ایسا سُنا ہے.لیکن باقی ساری آیتیں اور سورتیں ایسی ہیں جن میں کسی کے ہیں، کسی کے
پچاس اور کسی کے سو گواہ تھے اور بہت سے حصوں کے ہزاروں گواہ موجود تھے.بہر حال وہ
شہادت جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریر سے ثابت ہوتی تھی خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کے املاء اور لکھوانے ثابت ہوتی تھی.پھر زبانی گواہ آتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم نے رسول کریم
سے ایسا سنا یا ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے ایسا پڑھا ہے وہی قطعی اور یقینی سمجھی
جاتی تھی اور اسی قسم کی شہادتوں کے بعد ہی قرآن کریم میں کوئی آیت شامل کی جاتی تھی.( تفسیر کبیر جلد 10 صفحہ 85،84 تفسیر القریش:2)
اس طریقہ کار سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ حضرت عمرؓ کے اس قول کے کیا معنے ہیں کہ ” قراء کی شہادت
مختلف مقامات پر اسی طرح کثرت سے ہوتی رہی تو قرآن کا ایک کثیر حصہ ضائع ہو جائے گا واضح سی بات ہے
کہ حضرت عمر تحریرات کے ضائع ہونے کا ذکر نہیں کر رہے بلکہ صحابہ کی شہادت سے ہونے والے نقصان کا ذکر
کر رہے ہیں اور وہ نقصان ایسا ہے کہ صحابہ کے بعد اس کا مداوا بھی نہیں ہو سکے گا.وہ نقصان یہی تھا کہ صحابہ کی
Page 107
عہد خلافت راشدہ میں جمع و تدوین قرآن
91
شہادت کے ساتھ ہی وہ گواہی بھی دم تو ڑ دیتی جو صرف صحابہ بھی دے سکتے تھے.انہوں نے رسول کریم سے قرآن کریم
سیکھا تھا اور وہی یہ گواہی دے سکتے تھے کہ موجودہ دور میں موجود قرآن کریم وہی ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
پر نازل ہوا اور آپ نے امت کو دیا.پس اگر بر وقت اقدام نہ کیا جاتا تو یہ عظیم الشان گواہی ضائع ہو جاتی اور ایک
حصہ کثیر کے بارہ میں یہ شک پیدا ہو جاتا ہے کہ چند صحابہ نے اکٹھا کیا ہے قرآن اس لیے نہ جانے کتنا صحیح ہے.ابنِ ابی داؤد اپنی کتاب المصاحف میں ایک روایت درج کرتے ہیں کہ:
و ذلك فيما بلغنا حملهم على ان تتبعوا القرآن فجمعوه في الصحف في
كثير
خلافة ابی بکر خشية ان يقتل رجال المسلمين في مواطن معهم
من القرآن فيذهب بما معهم من القرآن ولا يوجد عند احد بعدهم
ابن ابی داؤد: كتاب المصاحف الجزء الاول صفحه 23)
ہمارے علم کے مطابق حضرت
ابوبکرؓ کے عہد خلافت میں انتہائی کوشش کر کے قرآن کریم جمع
کرنے کا قدم اس ڈر سے اُٹھایا گیا کہ اگر مسلمان کثرت سے شہید ہوتے گئے تو قرآن کریم کا
وہ حصہ جو ان کے پاس ہے اور ان کے علاوہ اور کسی کے پاس نہیں ہے وہ ضائع ہو جائے گا.پھر اُس دور کے حالات کو مد نظر رکھ کر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اور بھی کئی ضمنی فوائد حاصل ہوئے اور
بعض ایسے معاملات حل ہوئے جو آئندہ شکوک و شبہات کا موجب ہو سکتے تھے.مثلاً مختلف صحابہ کے پاس اپنی
اپنی ضرورتوں کے تحت جمع کیے ہوئے قرآن کریم کے نسخے موجود تھے.کیونکہ بعض صحابہ نے جو حصہ قرآن انہیں
حفظ نہیں تھا وہ اکٹھا کر لیا ، یا یہ کہ نزول کے ساتھ ساتھ قرآن کے متن کا کچھ حصہ تحریر کر لیا.یا چند سورتیں برکت
کے لیے لکھ لیں (بخاری کتاب فضائل القرآن باب تعليم الصبيان القرآن) پھر صحابہ ذاتی طور پر جمع کر رہے تھے اور
یہ بھی ممکن تھا کہ بہت سے صحابہ ایسے ہوں جنہوں نے اپنے تحریر کردہ قرآن کریم کے حصہ کو رسول کریم صلی اللہ
علیہ والہ وسلم کے حضور پیش کر کے اسے مستند نہ بنایا ہو.جبکہ تحریر کا رواج بھی نہ تھا اور نہ ہی اتنی مشق تھی اس لیے
ممکن تھا کہ غلطیاں بھی ان نسخوں میں راہ پا چکی ہوں.پھر یہ بھی ممکن ہے کہ ان نسخوں میں آیات کی ترتیب مختلف
ہو اور ایسی صورت ہو کہ فرض کریں کسی صحابی نے سورۃ البقرۃ کی 1 تا 25 تک آیات درج کی ہوں اور پھر 30 تا
287 بھی درج کی ہوں.مگر آیات 26 تا 29 کسی سفر یا اور مصروفیت کی وجہ سے درج نہ کر سکا ہو ممکن تھا آئندہ
زمانہ میں ان نسخہ جات کو لے کر ہی اعتراضات اٹھائے جاتے کہ ان میں فرق ہے.حضرت
ابو بکر ا گر فردا فردا تمام
صحابہ کے نسخوں کو چیک کر کے ان کی غلطیوں کی نشان دہی کرتے اور فردا فردا سب کو زیڈ کے صحیفہ پر متفق کرتے اور
ان کی تسلی کرواتے تو یہ بہت محنت طلب اور لمبا کام ہو جاتا اور امت کی متفقہ گواہی بھی نہ ملتی.پھر اس میں ایک یہ
Page 108
الذكر المحفوظ
92
قباحت بھی تھی کہ کوئی اپنی غلطی تسلیم کرتا اور کوئی حضرت ابوبکر کے صحیفہ کو غلط قراردیا.مگر اس طرز عمل میں یہ فائدہ تھا
کہ جب ایک شخص غلطی خوردہ ہو اور باقی قوم اس غلطی پر گواہی دے رہی ہو تو اس طرح غلطی خوردہ کو جلد اور مکمل تسلی
ہو جاتی ہے نیز آئندہ زمانہ میں معترضین کو اعتراض کرنے کا جائز موقع بھی نہیں ملتا کیونکہ یہ سب صحابہ اپنے اپنے
نسخوں
کی اغلاط تسلیم کر رہے تھے اور حضرت
ابو بکر کے نسخہ سے متفق ہورہے تھے.پس ان سب اور دیگر بہت سی ممکنہ
حکمتوں
کو مدنظر رکھتے ہوئے حضرت عمرؓ نے حضرت ابو بکر کی خدمت میں یہ تجویز پیش کی اور حضرت ابوبکر نے بہت
غور و فکر اور تدبر کے بعد نے اس تجویز کو قبول کیا اور امت مسلمہ کی نگرانی میں اور اسے گواہ بناتے ہوئے ایک مرکزی
نسخہ تشکیل دینے کرنے کا پہاڑ منتقل کرنے سے زیادہ مشکل مرحلہ طے کیا.یادر ہے تمام تر ممکنہ شبہات کو جڑ سے ہی ختم کرنے اور قرآن کریم کے بارہ میں تمام شکوک کا قلع قمع کرنے
کے لیے وہی طریقہ اختیار کیا گیا جو آنحضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے دعویٰ نبوت کے وقت اپنی صداقت کے
ثبوت کے طور پر اختیار کیا تھا.یعنی سب سے پہلے قوم کو گواہ بنایا کہ تم بتاؤ کیا میں نے کسی ادنی سے معاملہ میں بھی
کبھی جھوٹ بولا ہے؟ کیونکہ کوئی قوم خواہ کتنی ہی بددیانت کیوں نہ ہو اجتماعی طور پر جھوٹ نہیں بول سکتی کجا ایسا جھوٹ
بولیں کہ بعد میں اس کا ذکر ہی نہ کریں اور بالکل ہی خاموش ہو جائیں.پھر بعد میں اسی قوم نے حجۃ الوداع کے
موقع پر اس بات کی گواہی دی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے قرآن کریم کو کامل راستبازی، دیانتداری،
امانت داری اور کمال احتیاط اور حفاظت کے ساتھ بنی نوع کے سپرد کر دیا ہے.(بخاری کتاب الحج باب
خطبة بمنى ) اب حضرت ابو بکر نے قرآن کریم کی حفاظت کے معاملہ میں اسی امت کو گواہ بنایا جسے رسول کریم
صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے گواہ بنایا تھا.وہی امت جو اپنی وفاداری اور جانثاری کے ان گنت ناقابل تردید واقعات
سے اپنا صدق وصفا ثابت کر چکی تھی.جنہوں نے انفرادی اور اجتماعی قربانیوں کے میدانوں میں بار ہا ثابت کیا
کہ وہ اپنے اموال کے بدلے، اپنی جانوں کی قیمت اور اپنے پیاروں کی جانوں کی قیمت پر بھی ہمیشہ اس الہی
امانت کی حفاظت کرتے آئے ہیں اور کرتے رہیں گے.پھر اسی وفاداری کا عملی اظہار یہ امت اپنے آقا کی
وفات کے فوراً بعد ایک مرتبہ پھر آپ کے پہلے جانشین کی امامت میں کر چکی تھی یعنی انتہائی خطرہ کی حالت میں
بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی زندگی میں دیے گئے ایک حکم کو ان کی وفات کے بعد اس عزم کے ساتھ
پورا کر رہی تھی کہ اگر مدینہ کی گلیوں میں عورتوں اور بچوں کی لاشیں کتے بھی تھیٹتے پھریں پھر بھی وہ لشکر ضرور جائے
گا جس کے کوچ کا حکم رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے دیا تھا ( بحوال تفسیر کبیر جلد6از رتفسیر النور 56 صفحہ 385 ) پس
اب اُسی جانشین کی سرکردگی میں اس الہی امانت پر اس گواہی کے لیے اُسی امت کو طلب کیا جار ہا تھا کہ آؤ اور اس
الہی امانت کے غیر مبدل ہونے پر گواہ بن جاؤ جس کی حفاظت کے لیے تم نے ہر قسم کی قربانی دی ہے کہ یہد الہی امانت
Page 109
عہد خلافت راشدہ میں جمع و تدوین قرآن
93
بعینہ اسی حالت میں ہے جیسی رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے تمہیں دی تھی اور جس کی حفاظت کے لیے تم
اب تک قربانیاں کرتے آرہے ہو.جس کی حفاظت تم نے اپنے بڑھاپے کے سہارے، اپنے سہاگ، اپنے
بھائی ، اپنے بیٹے ، اپنے باپ ، اپنی مائیں، اپنی بہنیں ، اپنی بیٹیاں قربان کر کے اپنے وطن چھوڑ کے، اپنا سب کچھ
تیاگ کے کی ہے.آؤ اور تسلی بھی کر لو اور آئندہ کے لیے گواہ بھی بن جاؤ کہ اب تک جس امانت کی حفاظت تم
اپنے آقا کی سرکردگی میں کرتے رہے ہو، آج کتابی شکل میں بھی وہ بعینہ لفظ بلفظ محفوظ کی جا رہی ہے جیسی کہ تمہارا
آقا تمہیں دے کر گیا ہے.یادر ہے کہ کوئی قوم ایسی خاموشی کے ساتھ کسی بڑی بددیانتی پر اکٹھی نہیں ہوئی کہ تاریخ
اس کا ذکر تک نہ کرے اور پھر اب تو گواہ بنائی جانے والی قوم بھی ایسی تھی کہ جن کی اخلاقی حالت بھی اس درجہ اعلیٰ
اور ارفع تھی کہ کسی ادنی سی بددیانتی پر بھی اتنی خاموشی سے متحد ہو جانا ان کے لیے ناممکن تھا اور اس لیے بھی ناممکن
تھا کہ قرآن کی حفاظت کے لیے قبل ازیں بڑی بڑی قربانیاں دے چکے تھے.پھر سونے پر سہا گہ یہ کہ انتظام ایسا
اعلیٰ کر دیا گیا کہ اُن حالات میں بددیانتی کا ارتکاب ناممکن ہو گیا تھا.پس اعلان عام کیا گیا کہ جس شخص کے پاس بھی آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تصدیق شدہ قرآن کریم کا کوئی
حصہ حفظ میں یا تحریری شکل میں موجود ہو وہ لے آئے.تمام صحابہ اپنی اپنی مستند تحریرات لے کر آتے اور حفاظ کرام
اور تحریرات دونوں میں مطابقت دیکھی جاتی.ہر لفظ پر کم از کم دو حفظ کی اور دو تحریر کی گواہیاں اکٹھی ہوتیں اور
پوری تسلی کے بعد ہر آیت کو درج کیا جاتا.پس وہ امت جو براہ راست صاحب قرآن صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے
قرآن حفظ کر چکی اور سیکھ چکی تھی ہر ایک لفظ کے استناد پر گواہ بن رہی تھی اور اس عظیم الشان اور نا قابل تردید
گواہی سے قرآن کو مرکزی کتابی شکل میں پیش کیا جارہا تھا.ہر صحابی انفرادی طور پر گواہ بن رہا تھا کہ یہ وہی قرآن
ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے امت کو دیا.اور پھر تاریخ گواہ ہے کہ قرآن کریم کے معاملہ میں
چھوٹے سے چھوٹے اختلاف پر بپھرے شیروں کی طرح اُٹھ کھڑے ہونے والے کس خاموشی سے اور اطمینان
سے اس کام
کو مکمل کرتے ہیں اور کوئی معمولی سا اختلاف بھی سر نہیں اٹھاتا.اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ساری امت
پوری طرح مطمئن تھی کہ سب کچھ بعینہ اس طرح محفوظ کیا جا رہا ہے جیسا رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے تحریر
کروا کر اور حفظ کروا کر محفوظ کروایا تھا.اب سے پہلے جب بھی کبھی اختلافی صورت پیش آئی خواہ وہ اختلاف کتنا
ہی ادنی کیوں نہ ہو اس کا فیصلہ رسول کریم سے لیا اور تاریخ میں اس کا ذکر محفوظ کیا.اب بھی اگر کوئی اختلاف ہوتا
تو ضرور اس کا ذکر کیا جاتا.نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جمع قرآن کے سلسلہ میں حفاظت کے تمام تقاضے
بتمام و کمال پورے کیے جارہے تھے.حضرت ابوبکر کی سرکردگی میں تیار کیے جانے والے اس نسخہ کو مصحف اتم کہا
جاتا ہے.مستشرقین کبھی عدم علم اور کبھی دجل کی راہ سے شکوک پیدا کرنے کے لیے یہ وساوس پیدا کرنے کی
-
Page 110
الذكر المحفوظ
94
کوشش کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر کے دورِ خلافت میں بہت سے صحابہ کے باہمی مختلف نسخے موجود تھے لیکن یہ
جھوٹ ہے.اس بارہ میں تفصیل سے بات آئندہ سطور میں اپنے موقع پر ہوگی.یہاں
اتنا کہنا کافی ہے کہ اگر مختلف
نسخے ہوتے تو ضرور پیش کیے جاتے.لیکن صحابہ کا مصحف اتم پر اجماع
کرنا بتا تا ہے کہ کوئی حقیقی اختلاف نہیں تھا.پھر یہ پہلو بھی مد نظر رہے کہ آنحضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی وفات کے بعد حالات بے حد مخدوش تھے اور
مخالفت کا بازار بھی گرم تھا.تمام دشمن چوکنے تھے کہ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے لہذا
اب شائد اس امت کو آسانی سے برباد کیا جا سکے.اگر کوئی بھی ایسا قدم اُٹھایا جاتا جو حفاظت قرآن کے لحاظ سے
کمزور ہوتا تو ضرور دشمنان اسلام شور کرتے.لیکن اس شور و شر کے زمانہ میں ہر قسم کی احتیاط برتی گئی اور تمام
را ہیں حفاظت کی اختیار کی گئیں تا کہ کسی دیانت دار محقق کو شبہ اور شکایت کا ادنی سا موقعہ بھی نہ ملے.اس ضمن میں ایک یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ روایات میں یہ ذکر ملتا ہے کہ سورۃ الاحزاب یا سورۃ التوبہ
کی آخری آیت صرف حضرت ابوخزیمہ لائے اور کوئی صحابی نہیں لائے.اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ یہ آیات اور
کہیں لکھی ہوئی موجود نہیں تھیں.قرآن کریم رسول کریم کے زیر نگرانی تحریری صورت میں جمع کیا جاچکا تھا.پس
جب یہ کہا جائے کہ صرف فلاں صحابی کوئی آیت لایا تو اس سے مراد ہے کہ اُن صحابہ کے علاوہ، جن کے سپرد
آنحضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے دور میں جمع قرآن اور کتابت قرآن کا کام تھا، باقی صحابہ میں سے صرف ایک
صحابی ایسے تھے جنہوں نے آنحضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی طرف سے تصدیق محمدہ آیت اپنے پاس تحریری
صورت میں محفوظ کی ہوئی تھی.غیر تصدیق شدہ جانے کتنے نسخے تھے جن میں یہ آیت درج تھی.علامہ سیوطی نے
اتقان میں اور مولوی صدیق حسن صاحب نے تاریخ القرآن میں یہی رائے درج کی ہے.بہر حال اگر کسی کی
رائے اس رائے کے مؤید نہ بھی ہوتی تو بھی تاریخی حقائق کی روشنی میں یہی بات درست قرار پاتی ہے.کسی حافظ قرآن
کا بھی اس آیت سے کوئی اختلاف نہیں تھا اور نہ ہی کاتبین وحی میں سے کسی نے اختلاف کیا.گویا ان کا تبین کو بھی
جنہوں نے آنحضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے زیر نگرانی قرآن تحریر کیا تھا اور حفاظ کو بھی اس آیت کے بارہ میں کوئی
شبہ نہیں تھا.صرف ایک یہی آیت تھی جس کی مستند تحریر کاتبین وحی کے علاوہ صرف ایک صحابی کے پاس تھی.اس
آیت کے بارہ میں کوئی بے چینی پیدا ہوئی ہوتی تو ضرور اس کا ذکر ملتا اور لطف کی بات یہ کہ ان صحابی کی گواہی کو
رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے دو صحابہ کی گواہی کے برابر قرار دیا تھا.نیز یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ باوجود
اس کے کہ اس آیت میں کوئی اختلاف نہیں تھا مگر پھر بھی تاریخ میں اس کا ذکر محفوظ کیا گیا اس سے یہ امر مزید واضح
ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایسی آیت ہوتی جس میں حقیقی طور پر اختلاف پایا جاتا تو کیسے ممکن ہے کہ ذکر نہ کیا جاتا.پھر یہ
روایت اس حقیقت کا ایک اور بڑا لطیف ثبوت ہے کہ صحابہ کے پاس کثرت سے قرآن کریم کے مستند مسودات
Page 111
عہد خلافت راشدہ میں جمع و تدوین قرآن
95
موجود تھے.چنانچہ ایک آیت کی مستند تحریر جب صرف ایک صحابی کے پاس موجود پائی گئی تو صحابہ کو بہت عجیب لگا
اور انہوں نے اس کا ذکر کیا.اگر یہ تمام کارروائی اطمینان عام کے لیے تھی اور قو می گواہی اکٹھی کی جارہی تھی
تو ضرور تھا کہ ادنی سی بے اطمینانی کی حالت میں بھی صحابہ اعتراض کرتے.پھر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اس عظیم الشان خدمت کے پورا ہونے کے فوراً بعد جب کہ مرکزی نسخہ قرآن تیار
ہو چکا تھا، کسی صحابی کا اس کی نقل کرنا مذکور نہیں ہے.اگر قرآن کریم کے نسخہ جات موجود نہ ہوتے تو صحابہ کا قرآن کریم
سے عشق تو ایسا تھا کہ لاز م وہ نقول کروانے کے لیے ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے لیکن ایسا نہیں
ہوا.اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ یہ نسخہ تحریرات کی کمی دور کرنے کے لیے نہیں بلکہ صحابہ کی گواہی اور اطمینان عام
کے لیے مرتب کیا گیا تھا ورنہ لوگ اس کی نقول کروانے کو دوڑے پھرتے.حضرت عثمان کے دورِ خلافت میں یعنی قریباً
دس پندرہ سال بعد تک ، جب حضرت عثمان نے اس
کی نقلیں کروائیں، کسی نے عام استعمال نہیں کیا.یہ اسی صورت
میں ممکن تھا کہ قرآن کریم کے بکثرت نسخے موجود ہوں اور تعلیم عام ہو.خلاصہ یہ کہ یہ قدم حفاظت قرآن پر اجماع امت
کے لیے، اور حفاظت قرآن پر قوم کی گواہی اور اطمینان عام کے لیے اُٹھایا گیا تھا.حضرت ابوبکر کے اس اقدام پر غور
کرنے والے بعض مستشرقین بھی اس حقیقت تک پہنچے ہیں.چنانچہ Dr.Maurice Bucaille لکھتے ہیں
They had the advantage of being checked by people
who already knew the text by heart, for they had learned
it at the time of the Revelation itself and had
subsequently recited it constantly.Since then, we know
that the text has been scrupulously preserved, It does
not give rise to any problems of authenticity.(The bible The Quran and Science (translation from French by
Alastair D.Pannel and The Ahthor) Under Heading Conclusions
Pg 250-251)
انہیں (یعنی جن لوگوں کو حضرت ابو بکر نے جمع قرآن کا حکم دیا تھا ) یہ زائد فائدہ بھی حاصل
تھا کہ وہ (متن) اُن لوگوں سے چیک کروالیا جاتا تھا جنہوں نے وحی کے نزول کے وقت ہی
اسے حفظ کر لیا تھا اور بار بار اس کی تلاوت کرتے رہتے تھے.اس وقت سے، ہم جانتے ہیں کہ
قرآن کریم کا متن بلاشبہ محفوظ ہے اور اس کے استناد پر کوئی سوال نہیں اٹھتا.پھر حضرت عثمان کے عہد تک موافقین اور مخالفین کے پاس یہ مہلت تھی کہ اگر کسی کو کوئی بھی اختلاف ہو تو ضرور
اس کا ذکر کریں مگر سالوں پر سال گزرتے چلے گئے لیکن نہ امت مسلمہ کی طرف سے اور نہ ہی مخالفین کی طرف
سے کوئی آواز اُٹھائی گئی.آخر جب ایسے حالات پیش آئے کہ مناسب محسوس ہوا کہ اس مرکزی متفقہ صحیفہ پر ساری
قوم کو جمع کر دیا جائے تو صحابہ کے مشورہ اور رائے سے حضرت عثمان کی نگرانی میں متفرق طور پر صحابہ کے پاس
Page 112
الذكر المحفوظ
96
موجود ان قرآنی مسودات کو تلف کر دیا گیا جن کی مدد اور گواہی سے مرکزی صحیفہ تیار کیا گیا تھا اور دیگر قرآنی
مسودات بھی تلف کر دیے گئے جو عوام نے اپنے طور پر ذاتی استعمال کے لیے تیار کیے تھے.تاریخ اسلام اور عربی
زبان سے واقفیت رکھنے والا شخص جانتا ہے کہ یہ کام درست تھا اور اس کا مقصود نہ تو کوئی تحریف یابد یا تی تھی اور نہ
ہی متصور ہو سکتی ہے.یہ حفاظت قرآن کے ضمن میں ہی اُٹھایا گیا ایک اہم قدم تھا.اب صورت حال کچھ یوں تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو موجود نہیں تھے جو قرآن کریم کی محافظت کے
ضمن میں اُٹھنے والے اعتراضات کے سلسلہ میں حکم تھے.البتہ آپ کے زیر نگرانی تیار کیے گئے دیگر صحائف کے
ساتھ ساتھ ایک ایسا صحیفہ بھی موجود تھا جو امت مسلمہ میں مرکزی صحفہ قرار پایا.جس پر صحابہ کی متفقہ گواہی موجود تھی کہ یہ
صحیفہ قرآن بعینہ وہ ہے جو رسول کریم نے بنی نوع کے سپر د فر مایا اور اس میں کوئی رد و بدل اور کمی بیشی نہیں ہے.ایک پادری Jhon Gilchrist اس موقع پر ایک وسوسہ یہ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ حضرت ابوبکر کے
زیر نگرانی تیار کیا گیا نسخہ قرآن مرکزی نوعیت کا نہیں تھا بلکہ غیر اہم تھا.کیونکہ جب تیار ہو گیا تو حضرت عثمان کے
دور تک کبھی استعمال نہیں کیا گیا.بلکہ حضرت ابوبکر پھر حضرت عمر اور پھر حضرت حفصہ (رضوان اللہ علیہم اجمعین )
کی تحویل میں پڑا رہا.اگر یہ نسخہ ادنی سی بھی اہمیت کا حامل ہوتا ہے تو ضرور اس کا کثرت سے استعمال ہوتا.اس
طرح بلا استعمال رکھ دیا جانا بتاتا ہے کہ مرکزی اہمیت تو کجا اس کی ادنی سی بھی اہمیت نہیں تھی.اگر یہ پادری صاحب ذرا سا ہوش سے کام لیتے اور تاریخ کا اس طرح مطالعہ نہ کرتے جس طرح وہ بائبل کا مطالعہ
کرتے ہیں بلکہ ذرا سا عقل و خرد سے کام لیتے تو معلوم ہو جاتا کہ یہ نسخہ تو بے انتہا اہمیت کا حامل تھا.حضرت عمرؓ
نے اتنی بحث
و تمحیص کے بعد حضرت
ابو بکر کو راضی کیا تھا.پھر حضرت زیدہ بھی فرماتے ہیں کہ اس کی تیاری پہاڑ
کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقلی سے زیادہ مشکل کام تھا.کیا اس قدر مشکل کام
کا بیڑا اس لیے اٹھایا گیا کہ نیچے جو
نسخہ تیار ہو وہ بالکل ہی غیر اہم ہو؟ پھر یہ کام تھا بھی اس قدرا ہم کہ اس کا نہ کرنا حضرت عمر کے الفاظ میں گویا
قرآن کریم کا حصہ کثیر ضائع کرنے کے مترادف تھا.پھر اتنی کثرت سے نسخہ جات موجود ہونے کے باوجود اتنا
وقت صرف کر کے اور اس قدر محنت کر کے جو ایک نسخہ بنایا گیا کیسے ممکن ہے کہ اُس کی اہمیت ہی نہ ہو؟ پھر اس کے
استناد پر تمام تر شبہات کا قلع قمع کرنے کے لیے گواہیوں کا ایک عدیم النظیر سلسلہ چلا.کیا ایک ایسے غیر اہم نسخہ کی
تیاری کے لیے پوری قوم کی گواہیاں اکٹھی کی گئیں؟ پھر جس نہج پر گواہیاں اکٹھی کی گئیں وہ بھی فی ذاتہ بے نظیر
کام تھا.کیا جس نسخہ کے استناد پر رسول کریم کے سب صحابہ متفق تھے وہ نسخہ غیر اہم قرار دیا جاسکتا ہے؟ بے شمار
نسخوں کے موجود ہونے کے باوجود حضرت عثمان نے امت کو ایک صحیفہ پر متفق کرنے کے لیے جس نسخہ قرآن کو
چھا کیا وہ دوسرے نسخوں سے کم اہم تھا ؟ لازمی سی بات ہے کہ اُس وقت موجود نسخوں میں سب سے اہم نسخہ یہی تھا
Page 113
عہد خلافت راشدہ میں جمع و تدوین قرآن
97
تبھی اس کو چُنا گیا.کیا ان تمام امور سے صحیفہ کی اہمیت کا اور اس کی افادیت کا اندازہ نہیں ہوتا ؟ یہ کہنا کہ لوگوں
نے اس کا عام استعمال نہ کیا اس لیے معلوم ہوا کہ یہ غیر اہم تھا انتہائی بچگانہ بات ہے.ہاں محافظت قرآن کریم
کے سلسلہ میں شکوک پیدا کرنے کے لیے جن نسخوں کو اتنی اہمیت دیتے ہو وہ نسخے تو واقعی غیر اہم تھے اور وہی ایک
نسخہ اہم تھا جس کے استناد پر تمام امت اور مخالف و موافق متفق تھے.صرف اس لیے کہ اس
نسخہ کو عوام نے کثرت
سے استعمال نہ کیا پس ثابت ہوا کے یہ اہم نہیں تھا یہ تو ایک غیر معقول اور غیر مناسب سوچ ہے.اُس دور میں
قرآن کریم کی تحریرات بہت عام تھیں اور لوگوں کو کثرت سے قرآن کریم حفظ تھا اس لیے اس مخصوص نسخہ کی
ضرورت نہ پڑی.جب ضرورت پڑی تو پھر صرف اسی نسخہ کو استعمال کیا گیا اور کوئی دوسرا نسخہ استعمال نہیں کیا گیا.اس کی نقول کروائی گئیں اور سب عالم اسلام میں پھیلائی گئیں اور ان کو استعمال کیا گیا.ہر چیز کی اہمیت کا اندازہ صرف اس کے کثرتِ استعمال سے تو نہیں لگایا جاتا.کیا اگر اصل سنبھال کے اور
محفوظ رکھی گئی ہو اور نقول استعمال کی جاتی ہوں تو ایسا نسخہ غیر اہم ہو جاتا ہے؟ کسی تعلیم کی اصل اہمیت کا اندازہ تو
اس بات سے ہوتا ہے کہ وہ کس قدر عام ہے.اس کی اشاعت کس قدر ہے.کوئی قوم اسے کس قدر اہمیت دیتی
ہے.نہ کہ اسی وقت کوئی چیز اہم ثابت ہوتی ہے کہ اس کے اصل نسخہ کو ہر شخص کی پہنچ میں کر دیا جائے.اہم
مسودات تمام کے تمام کثرت سے استعمال کیے جاتے ہیں مگر نقول کی صورت میں.ایسا تو نہیں ہوتا کہ ہر شخص
اصل مسودہ لیے پھرتا ہے.اس اعتراض کا سیدھا سیدھا مطلب تو یہی نکلتا ہے کہ تمام اشیاء جو عجائب گھروں میں
رکھی ہیں یا حکومتی تحویل میں یا بینکوں کے لاکروں میں یا تجوریوں میں محفوظ پڑی ہیں ساری غیراہم ہیں.اگر اہم
ہیں تو کیوں ہر عام شخص کا ہاتھ اُن تک نہیں پہنچتا؟ بہت سی نادر کتب کے
قیمتی قلمی نسخے جولائبریریوں یا عجائب گھروں
میں محفوظ ہیں غیراہم ہیں ہاں ان نسخوں کی نقول بہت اہم ہیں کیوں کہ وہ عام شخص کی پہنچ میں ہیں.امت محمد یہ
میں تو قرآن کریم کی تعلیمات بہت عام تھیں اور حفظ اور تلاوت اور قرآنی تعلیمات کی نشر واشاعت بہت کثرت
سے ہوا کرتی تھی.پس یہ کہنا کہ خاص اس نسخہ کو عام طور پر استعمال نہ کیا گیا پس وہ غیر اہم تھا ایک غیر منطقی اور مبنی بر
تعصب نتیجہ ہے.جب قرآن کریم کے نسخہ جات کثرت سے موجود ہوں تو پھر اس ایک نسخہ کو جسے اس قدر محنت
اور مشقت سے تیار کیا گیا تھا، حفاظت کے نکتہ نظر سے محفوظ رکھنا کس طرح یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ غیر اہم تھا ؟ اس
سے تو یہ واضح ہوتا ہے کہ وہ خاص نسخہ دوسرے تمام نسخوں سے زیادہ اہم تھا.سوال یہ ہے کہ جب ضرورت پڑی تو
کیا پھر بھی اس نسخہ کو استعمال کیا گیا یا نہیں؟ یقیناً کیا گیا اور ہزاروں دوسرے صحائف کی موجودگی میں صرف اسے
ہی استعمال کیا گیا.تو کیا اس سے یہ ثابت نہیں ہو جاتا کہ وہ نسخہ تمام دیگر نسخوں سے زیادہ اہم تھا؟
خلاصہ یہ کہ قرآن کریم جو آنحضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے زیر نگرانی تحریری شکل میں نزول کے ساتھ ساتھ جمع
Page 114
الذكر المحفوظ
98
کیا جاچکا تھا مگر اس وقت اس کو ایک جلد میں پیش کرنا ناممکن تھا.رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی وفات کے
ساتھ جب قرآنی وحی مکمل ہونے کا علم ہو گیا تو ایک جلد میں جمع کرنا ممکن ہوا اور احتیاط کے تمام تقاضے پورے
کرتے ہوئے اس جلد پر تمام امت کی گواہی جمع کی جارہی تھی کہ یہ قرآن کریم بعینہ وہی ہے جو حضرت رسول
کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے امت کے سپرد کیا ہے.اور صحابہ نے آنحضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی وفات کے
بعد پوری دیانت داری کے ساتھ احتیاط کے تمام تقاضے پورے کرتے ہوئے انتہائی خوش اسلوبی سے یہ خدمت
سرانجام دی.یعنی قرآن کو آخری کتابی شکل میں محفوظ کرتے ہوئے اس کی صداقت اور استناد پر تمام قوم کی گواہی
بھی قائم کر دی اور ہمعصر مخالفین کی خاموشی اس پر ایک اور گواہ بن گئی.جس طرح آنحضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم
نے اپنے دعوی کی ابتداء میں اپنی قوم کو اپنی صداقت پر گواہ بنایا پھر وفات کے قریب قوم سے گواہی لی کہ آپ نے
اپنا فرض ادا کرلیا ہے اس طرح حضرت عمر کی تجویز اور اعانت سے حضرت ابوبکر کی سرکردگی میں حضرت زید بن
ثابت نے تمام امت کو اس بات پر گواہ بنایا کہ آج قرآن کریم بعینہ وہی ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم
سے امت نے سیکھا تھا.یہ تھاوہ مشکل کام جسے حضرت زیڈ نے پہاڑ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے سے
بھی زیادہ مشکل
قراردیا تھا.پس بفضلہ تعالیٰ یہ کام بپایہ تکمیل کو پہنچا.الحمد للہ.حضرت عثمان نے صحابہ کرام کے مشورہ اور اتفاق رائے سے اپنے دور خلافت میں اس نسخہ کو مملکت اسلامیہ
میں ایک انتظام کے تحت شائع اور رائج کر دیا.صحابہ کے دور میں قرآن کریم میں رد و بدل ناممکن تھا
قرآن کریم کی جمع و تدوین کے ضمن میں یہ حقیقت ثابت ہو چکی کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کو
پوری حفاظت کے ساتھ صحابہ کرام کے حوالے کر دیا اور اس سپردگی کے عمل میں ایسی کمال درجہ کی احتیاط برتی کہ
کوئی دوسری کتاب اس میں حصہ دار نہیں اور اس ضمن میں ایسے انتظامات فرمائے کہ صحابہ کے لیے قرآن کریم کی
حفاظت چنداں مشکل نہ رہی اور صحابہ نے کمال دیانت داری سے یہ قومی فریضہ سرانجام دیا.محافظت قرآن کریم کا ایک پہلو یہ بھی ہے جب قرآن کریم صحابہ کرام کے سپرد کیا گیا تو اس انداز اور ان
حالات میں کیا گیا کہ وہ اس میں کوئی رد و بدل کر ہی نہیں سکتے تھے.کیونکہ:
-1- تحریری صورت میں خوب پھیل چکا تھا.2- حفظ کے ذریعے ہزاروں سینوں میں محفوظ ہو چکا تھا.3- نماز میں تلاوت قرآن فرض تھی اس لیے ہر مسلمان کو کچھ نہ کچھ حصہ یاد کرنا ہوتا تھا جو نماز میں لوگوں کے
Page 115
99
عہد خلافت راشدہ میں جمع و تدوین قرآن
سامنے تلاوت کیا جاتا.پھر ہر رمضان میں نماز تراویح میں اس کی دہرائی ہوتی.-4 دن رات کلام الہی کی درس تدریس کا سلسلہ جاری تھا.ہر وقت اس کی تلاوت کی جاتی.اپنے اور بیگانے
سب اس کے ایک ایک لفظ کی صداقت کے گواہ تھے اور بلا مبالغہ یہ علم بھی چند صحابہ کے پاس محفوظ تھا کہ فلاں
آیت کس جگہ، کس موقع پر اور کن حالات میں نازل ہوئی.5.پھر جن لوگوں کے سپرد یہ امانت ہوئی تھی یعنی آنحضور کے صحابہ کا نمونہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ وہ اخلاق
عالیہ کے ایسے اعلیٰ اور ارفع مقام پر فائز تھے کہ ممکن ہی نہیں تھا کہ اخلاقی ، روحانی اور دنیاوی آداب کے نئے اور اعلیٰ
پیمانے قائم کرنے والی قوم ایک ایسی عظیم الشان قومی بددیانتی کی مرتکب ہو جاتی.ایک ایسی قوم کہ جس کے حالات کا
مطالعہ کرنے سے اس بات پر یقین ہو جاتا ہے کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ان لوگوں میں سے کوئی بھی ایسا ہو جس نے قرآن
کریم کے معاملہ میں ادنی سی بھی بد دیانتی کی ہو اور نہ ہی تاریخ میں کوئی ایسی مثال ملتی ہے.بلکہ جہاں ادنی سی بھی غلط
فہمی پیدا ہوئی تو حفاظت قرآن کے ضمن میں ایسی غیرت ایمانی کا نمونہ دکھایا کہ اگر کسی منافق یا مخالف کے دل میں
تبدیلی پیدا کرنے کی کوئی اُمید بھی ہوگی تو وہ بھی دم تو ڑگئی ہوگی.یہ ذکر گزر چکا ہے کہ کسی بھی قوم کا اس طرح خاموشی
سے کسی قومی بددیانتی پر متفق ہو جانا کہ کسی کو کانوں کان
خبر نہ ہو، ہرگز ممکن نہیں.انہوں نے تو قرآن کریم کی حفاظت
اور اشاعت کے لیے ایسے ایسے ہولناک مظالم برداشت کیے تھے کہ پڑھ کر ہی انسان کی روح تک میں لرزہ طاری ہو جاتا
ہے.پس اُن میں سے کسی ایک کے بارہ میں بھی یہ تصور نہیں کیا جاسکتا کجا یہ کہ پوری قوم کے بارہ میں سوچا جائے.6- پھر حضرت ابو بکر نے امت کی گواہی ڈلوا کر اور امت کو اعتماد میں لے کر حفاظت قرآن کے حوالہ سے پیدا
ہونے والے
تمام تر شبہات جڑ سے ختم کر دیے.7- حضرت عثمان نے اختلاف قراءت کا فیصلہ کر کے اور ایک قراءت پر امت کو جمع کر کے حفاظت قرآن کے
موضوع پر غلط فہمی کے آخری امکان کو بھی ختم کر دیا.پس کلام الہی اس درجہ احتیاط کے ساتھ آگے منتقل کیا گیا تھا کہ کوئی تبدیلی مکن ہی نہیں تھی جب تک کہ ساری قوم
اور ہزاروں ہزار جانثار، یک بیک غدار نہ ہو جاتے اور پھر اتنے بڑے پیمانہ پر تبدیلی کے بارہ میں ممکن ہی نہیں تھا کہ
تاریخ کی باریک بین نظروں سے چھپائی جاتی اور منتقل بھی اُن لوگوں کو کیا گیا جو اپنی جانوں اور مالوں کی قربانیوں کے
ساتھ ہر لحاظ سے آزمائے جاچکے تھے.وہ اس کے ایک ایک لفظ پر محاورۃ نہیں بلکہ حقیقت جان نچھاور کرنے کو تیار تھے
اور اس
کی عملی مثالیں بار ہا پیش کر چکے تھے اور ایسے نمونے دکھا چکے تھے کہ آج ان کو دیکھ کر مخالف آنکھ بھی یہ تسلیم کرنے
پر مجبور ہو جاتی ہے کہ وہ ایک باوفاقوم تھی اس بات کا ذکر H.M.Hyndman اپنے انداز میں یوں کرتا ہے:
"...This very human prophet of God had such a
remarkable personal influence over all with whom he
Page 116
100
الذكر المحفوظ
was brought into contact that, neither when a
poverty-stricken and hunted fugitive, nor at the height
of his prosperity, did he ever have to complain of
treachery from those who had once embraced his faith.(H.M.Hyndman: The Awakening of Asia, London 1919, p.9.)
اس خدا کے رسول بشر ( ﷺ) نے ایمان لانے والوں پر اپنی قوت قدسیہ کی ایسی تاثیر ڈالی
کہ نہ تو افلاس اور مصائب کی آندھیوں میں اور نہ ہی حالت کیسر میں کبھی اُن سے ادنی سی دھو کہ
دہی یا فریب کی شکایت ہوئی.پس اس درجہ باوفا اور پاکباز جانثاروں کے بارہ میں کیسے سوچا جاسکتا ہے کہ وہ بلا وجہ آن واحد میں غداری
کے مرتکب ہو گئے اور پھر غداری بھی ایسی کہ سب ہی اس پر متفق ہو گئے کہ قرآن کریم میں تحریف اور تغیر و تبدل کیا
جائے؟ کوئی ایک بھی حقیقت بیان کرنے والا نہ بچا اور اتنی خاموشی سے یہ کام کیا کہ ہمعصر مخالفین کو بھی کانوں
کان
خبر نہ ہوئی.ذرا تجزیہ تو کیجیے کہ تاریخ عالم کے اس سب سے بڑے فراڈ پر وہ لوگ متحد ہو گئے جن کی عورتیں
ابھی ابھی اس کلام کی حفاظت میں بیوہ ہوئی تھیں، جن کے یتیم بچے ابھی مدینہ کی گلیوں میں کھیل رہے تھے، جن
کی بوڑھی مائیں ابھی اپنے اُن جوان بچوں کی یاد میں اشک فشاں تھیں جن کی شہادت
کو زیادہ دیر
نہیں ہوئی تھی.ہاں کیسے ممکن ہے کہ وہ قوم غدار ہوگئی ہو جس نے اپنے رسول کے پہلے جانشین کی زبان پر اپنے آقا کی وفات کے
فوراً بعد یہ عہد کیا تھا کہ اگر مدینہ کی گلیوں میں کتے بھی عورتوں اور بچوں کی لاشوں کو نوچ رہے ہوں تب بھی وہ لشکر
ضرور جائے گا جس کو آنحضور تیار کر کے گئے ہیں.(بحوالہ تفسیر کبیر جلد 6 زیرتفسیر النور 56 صفحہ 385 ) جو اپنے آقا کی
وفات کے فوراً بعد بعینہ اسی طرح یمامہ کی جنگ میں اپنے جوانوں کے خون اسلام کی راہ میں بہا چکی تھی جس طرح
وہ اپنے آقا کی زندگی میں بہایا کرتی تھی.کیا ممکن ہے ایسی قوم جو وفاداری کے ایسے ایسے اعلیٰ انفرادی اور اجتماعی
نمونے دکھا چکی ہو کہ دنیا کی تاریخ میں پہلی بارہ نمونے دکھائے گئے ہوں، یک بیک غدار ہو جائے؟ کیسے ممکن
ہے کہ لاکھوں کی وہ تعداد اتنی خاموشی سے تاریخ انسانی کی سب سے بڑی اور اس قدر غیر ممکن العمل بددیانتی پر اکٹھی
ہوگئی ہو اور پھر اس صفائی کے ساتھ کہ کسی دوسرے کو اس کی بھنک بھی نہ پڑی ہو؟ بہر حال ہم گزشتہ سطور میں عقلی طور
پر ثابت شدہ اس حقیقت کو نقلی قرائن اور تاریخی واقعات کی روشنی میں بھی دیکھ چکے ہیں کہ قرآن کریم رسول کریم صلی
اللہ علیہ والہ وسلم کے بعد بدلا نہیں گیا بلکہ آج بھی ایسا ہی ہے جیسا کہ رسول کریم نے امت کے حوالے کیا تھا.قرآن مجید کے اعراب (حرکات ) و نقاط
حضرت علی نے اپنے دور خلافت میں نحو ( یعنی عربی گرائمر ) کے چند قواعد بتا کر اپنے ایک گورنر ابوالاسود
دولی کو ارشاد فرمایا کہ اس کے مطابق مزید قواعد وضع کرو ( تاریخ الخلفاء حالات حضرت علی صفحہ 228) اس سے قبل
Page 117
عہد خلافت راشدہ میں جمع و تدوین قرآن
101
حضرت
عثمان انہیں کو قرآن مجید پر اعراب لگانے کا حکم دے چکے تھے تا غیر عرب بھی قرآن کریم صحیح طور پر پڑھ
سکیں اور بسہولت اس کی تعلیمات سے بہرمند ہو سکیں لیکن آپ بوجوہ فوری طور پر اس حکم کی تعمیل نہ کر سکے.حضرت عثمان نے یہ حکم اختلاف قراءت کا مسئلہ حل کرنے کے بعد دیا تھا.42ھ میں حضرت امیر معاویہؓ نے
ابوالاسود کو بنی امیہ سے اختلافات رکھنے کی بناء پر معزول کر دیا.فراغت میسر آنے پر انہوں نے خلفاء کے ارشاد
کی تعمیل میں ایک رسالہ قواعد نحو کے بارہ میں تحریر کیا.اسی طرح قرآن مجید پر اعراب بھی لگائے.مگر یہ اعراب
آج کل کے اعراب جیسے نہ تھے.بلکہ نقطوں کی صورت میں تھے.(عرض الانوار از قاضی عبدالصمد سیوہاروی مطبوعہ حمید
برقی پریس دہلی.سن اشاعت 1359 طبع اوّل صفحہ 73 74) امام ابوعمر وعثمان بن سعید الدانی نے لکھا ہے کہ ابوالاسود نے
ایک آدمی سے کہا کہ قرآن کریم لے لو اور ایک رنگ تحریر کی روشنائی کے رنگ سے مختلف لیا اور اس سے کہا کہ اگر
میں اپنا منہ کھولوں تو حرف کے اوپر ایک نقطہ (زبر) لگانا اور اگر منہ کو نیچے کی طرف مائل کروں تو نیچے ایک نقطہ (زیر)
لگانا اور اگر اپنے منہ ملادوں تو ایک نقطہ حرف کے آگے (پیش) اور اگر ان حرکات کے ساتھ غنہ بھی ہو تو دو نقطے
( تنوین ) لگانا.اس نے ایسا ہی کیا.(بحوالہ عبد الصمد صارم الازھری : تاریخ القرآن، ایڈیشن 1985 ندیم یونس پرنٹرز لاہور،
پبلشرز : مکتبہ معین الادب اردو بازار لا ہور صفحہ 123 )
6699
اس وقت تک قرآن کریم خط کوفی میں لکھا جاتا تھا جس میں حروف پر نقطے نہیں ہوتے تھے مگر “ اور ”
اور ” اور ” اور ”س“ اور ”ش“ کی طرز کتابت میں فرق تھا جس کو عرب بخوبی پہچانتے تھے اور
پڑھنے والے بالکل صحیح پڑھتے تھے.نیز کثرت تلاوت کے شوق اور حفاظ کی کثرت کی وجہ سے غلطی کا راہ پا جانا غیر
ممکن تھا.رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم حضرت ابوبکر اور حضرت عثمان ، متینوں مبارک ہستیوں کے عہد میں
قرآن مجید ایک ہی رسم الخط میں لکھا گیا اور حضرت عثمان کے عہد کے نسخے جو محفوظ ہیں وہ خط کوفی میں ہیں اور
ان میں حروف کے نقطات نہیں ہیں.( سیارہ ڈائجسٹ قرآن نمبر جلد سوم صفحہ 281 282 شمارہ: اپریل 1970 شمارہ نمبر 4)
آج تمام امت مسلمہ میں ایک نظام کے تحت شائع ہونے والے نسخہ ہائے قرآن میں اس بات کا خاص التزام کیا
جاتا ہے کہ کتابت قرآن کے لیے رسم الخط جو بھی اپنایا جائے قرآن کریم کے الفاظ کو انہی حروف کے ساتھ لکھا جائے جن
حروف کے ساتھ حضرت عثمان کے دور میں صحابہ کے زیر نگرانی تحریر کیا گیا.حضرت عثمان نے کتابت کے بعض
معمولی فرقوں کو دیکھ کر فرمایا تھا کہ عرب قوم اپنے بحسن سے ان کو درست کر لے گی.چنانچہ قربان جائیں رسول امین
کے اُن امانت دار پیروکاروں کے کہ جنہوں نے کتابت کی ان معمولی اغلاط کی اصلاح بھی اپنے لیے جائز نہ کبھی
اور آج مستند نسخوں میں لفظ اُسی طرح لکھا جاتا ہے جس طرح حضرت عثمان کے وقت لکھا گیا.ان اغلاط کی درستگی کرنا
Page 118
الذكر المحفوظ
102
علم کتابت قرآن کے مطابق غلطی قرار دیا گیا اور اس طرح حفاظت قرآن کریم کے غیر معمولی ہونے کے بارہ میں ایک
عظیم مثال قائم ہوئی.آج مستند نسخہ ہائے قرآن کریم میں پائی جانے والی کتابت کی یہ معمولی اغلاط محافظت قرآن کا
ایک لطیف اور خوبصورت ثبوت ہیں.65ھ میں حجاج بن یوسف نے سکھی بن عمر اور نصر بن عاصم کو مقرر کیا جنہوں نے حروف کے باقاعدہ نقطے
وضع کیے جو آج تک رائج ہیں.اب صورت حال یہ تھی کہ حروف کے اپنے نقطے بھی تھے اور حرکات کی علامت کے
طور پر نقطے پہلے لگائے جارہے تھے.اس لیے ان دونوں قسم کے نقطوں میں فرق رکھنے کے لیے جو نقطے حرکات کی
علامت کے طور پر تھے انہیں سرخ روشنائی سے لکھا جاتا اور حروف کے اپنے نقطے سیاہی سے لکھے جاتے.(كتاب المصاحف الجزء الثالث:صفحه 90)
سیارہ ڈائجسٹ ، قرآن نمبر ، حوالہ مذکور )
پھر بنو عباس کے زمانہ میں (غالباً مامون الرشید کے عہد میں ) مشہور عالم خلیل بن احمد (متوفی 175ھ) نے
اہم خدمات سرانجام دیں.اس نے ہمزہ اور شد کی علامت مقرر کرنے کے علاوہ بنیادی کا رنامہ یہ سرانجام دیا کہ
حرکات (زیر، زبر، پیش ) کی وہ شکل ایجاد کی جو آج بھی رائج ہے.جلال الدین سیوطی ؛ الاتقان فی علوم القرآن جلد 2 صفحہ 540، ناشر مطبعه مجازی قاهره)
رسم الخط کی تاریخ میں عباسی وزیرا بن مطلہ (متوفی 328ھ ) نے بڑی اہم کامیابی حاصل کی.اس نے خط نسخ
ایجاد کیا.یہ خط بہت سادہ ، واضح اور آسان ہے.اس طرح چوتھی صدی ہجری کے اواخر اور پانچویں صدی کے
آغاز میں خط کوفی متروک ہو گیا اور اس کی جگہ خط رح نے لے لی.ساتویں صدی میں امیر علی تبریزی نے خطِ نسخ
میں مزید اصلاح کر کے نیا خط، خط نستعلیق ایجاد کیا.یہ دونوں خط اب بھی مقبول اور مستعمل ہیں.سیارہ ڈائجسٹ، قرآن نمبر، حوالہ مذکور صفحہ 284)
اب یہ تو واضح ہو گیا کہ قرآن کریم کا ایک خاص متن تھا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے اپنی نگرانی میں
ہی محفوظ کر دیا تھا اور گزشتہ سطور میں ہم یہ بھی ثابت کر آئے ہیں کہ صحابہ کے دور میں قرآن کریم میں کوئی تبدیلی
نہیں ہوئی مگر پھر بھی بعض روایات کا سہارا لے کر شکوک پیدا کیے جاتے ہیں.مثلاً ترتیب قرآن کے معاملہ میں
کہا جاتا ہے کہ اصل ترتیب بدل دی گئی اور صحابہ نے قرآن کریم کی سورتوں کی ترتیب لگائی.اسی طرح اختلاف
مصاحف، اختلاف قراءت وغیرہ کے معاملات میں شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے.آئندہ صفحات
میں باری باری ان بڑے بڑے موضوعات کا محاکمہ کرتے ہیں جنہیں اکثر مخالفین اسلام کسی نہ کسی انداز میں اپنی
جہالت کی وجہ سے یا عوام الناس کی عدم واقفیت کا فائدہ اُٹھانے کے لیے بار بار پیش کرتے ہیں.
Page 119
قرآن کریم میں تحریف کے الزامات کے جواب
103
باب دوم
قرآن کریم میں تحریف کے الزامات
کے جوابات
در اصل تہذیب حقیقی کی راہ وہی راہ ہے جس پر انبیاء علیہم السلام نے قدم مارا ہے جس میں
سخت الفاظ کا داروئے تلخ کی طرح گاہ گاہ استعمال کرنا حرام کی طرح نہیں سمجھا گیا بلکہ ایسے
درشت الفاظ کا اپنے محل پر بقدر ضرورت و مصلحت استعمال میں لانا ہر یک مبلغ اور واعظ کا فرض
وقت ہے جس کے ادا کرنے میں کسی واعظ کائستی اور کا بلی اختیار کرنا اس بات کی نشانی ہے کہ
غیر اللہ کا خوف جو شرک میں داخل ہے اس کے دل پر غالب اور ایمانی حالت اس کی ایسی کمزور
اور ضعیف ہے جیسے ایک کیڑے کی جان کمزور اور ضعیف ہوتی ہے.( حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی معہود علیہ السلام)
شیطانی آیات 105
اختلاف مصاحف - 269
واقعہ ابی سرح - 111 اختلاف قراءت - 285
ترتیب قرآن - 177
متفرق الزامات
آیت رجم
256-
311-
Page 121
قرآن کریم میں تحریف کے الزامات کے جواب
105
شیطانی آیات
شیطانی آیات کا قصہ ایک ایسا قصہ ہے جو کہ مخالفین کی طرف سے تکرار کے ساتھ یہ ثابت کرنے کے لیے پیش کیا
جاتا ہے کہ رسول کریم نے قرآن کریم میں نعوذ باللہ رد و بدل کیا ہے.ذیل میں ہم یہ دیکھیں گے کہ شیطانی آیات کا
قصہ در اصل محمد رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کی بددیانتی کو ظاہر کرتا ہے اور یہ بھی دیکھیں گے کہ رسول کریم صلی
اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات اخلاق عالیہ کی ایسی کامل اور جامع صورت تھی اور آپ اخلاق فاضلہ کے ایسے بلند
مقام پر فائز تھے کہ آپ کی سیرت کا مطالعہ دیانت دار قاری کو اس یقین محکم پر قائم کر دیتا ہے کہ آپ ایسی ادنی ادنیٰ
باتوں سے بالا.بہت بالا تھے.آپ کے بارہ میں سوچا بھی نہیں جاسکتا کہ زندگی کے کسی موڑ پر آپ کبھی ادنی سی بھی
بددیانتی کی مرتکب ہوئے ہونگے.ابن وراق بھی خدا تعالیٰ کے قائم فرمودہ حفاظت قرآن کے بے نظیر انتظام کے ہر
پہلو کے بارہ میں عام قاری کے دل میں شک پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہو ا اب یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ
قرآن کریم جن لوگوں کے ہاتھوں سے ہم تک پہنچا ہے وہ دیانت داری کے معیار پر پورا نہیں اترتے.اور یہ تاثر پیدا
کرنے کی کوشش میں خود بددیانتی کی ایک اور فتیح مثال قائم کر دی ہے.چنانچہ سب سے پہلے سید المعصومین،
الصدوق الامین، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کو نشانہ بنانے کی پلید جسارت کرتا ہے.ابن وراق کہتا ہے:
We also have the case of the Satanic Verses, which
clearly show that Muhammad himself suppressed some
verses.(Ibn Warraq: Why I am Not A Muslim, Prometheus Books, New
York, 1995, under heading; The Koran: Pg 112)
”ہمارے پاس شیطانی آیات کا قصہ بھی ہے جو یہ واضح کرتا ہے کہ محمد (ﷺ) نے خود بھی
کچھ آیات خرد برد کی ہیں.“
تاریخ اسلام میں صرف ایک قصہ پیش کیا جاتا ہے جس میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نے معمولی رد و بدل سے کفار کو خوش کرنے کی کوشش کی تھی.جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ بھی کفار کی ہی ایک
سازش تھی جو حالات اور واقعات کے مطالعہ سے خوب کھل کر سامنے آجاتی ہے.اس واقعہ کے بارہ میں
حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب خلیفتہ امسیح الثانی الصلح الموعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں:
مسلمان مفسر کہتے ہیں کہ یہ آیتیں جو آپ نے پڑھیں کہ وتلك الغرانيق العلى و
ان شفاعتهن لترتجی یہ قرآن کا حصہ نہیں تھیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے بعد میں ان کو منسوخ
کر دیا.چنانچہ موجودہ قرآن میں یہ آیتیں نہیں ہیں.وہ اس کہانی کی حقیقت یہ بیان کرتے ہیں
Page 122
الذكر المحفوظ
106
کہ سورہ حج میں یہ آیت آتی ہے کہ وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ وَّلَا نَبِيِّ إِلَّا إِذَا
تَمَنَّى اَلْقَى الشَّيْطَنُ فِی أُمُنِيَّتِهِ یعنی ہم نے تجھ سے پہلے کوئی رسول اور نبی نہیں بھیجا مگر اس
کی یہ حالت تھی کہ جب کبھی وہ وحی پڑھتا تھا شیطان اُس کی وحی میں اپنی طرف سے کچھ ملا دیتا تھا.پھر بعد میں خدا تعالیٰ شیطانی وحی کو منسوخ کر دیتا تھا.اسی طرح جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نے سورۃ نجم کی آیتیں خانہ کعبہ میں پڑھیں تو شیطان نے (نعوذ باللہ من ذالک ) آپ کی وحی
میں یہ بات ملادی كه وتلك الغرانيق العلى و ان شفاعتهن لترتجي جب رسول
کریم کی زبان سے یہ الفاظ نکلے تو مکہ کے کفار نے سمجھا کہ آپ نے اپنے دین میں کچھ تبدیلی
کر دی ہے اور آپ کے ساتھ سجدہ میں شامل ہو گئے.جب مکہ میں شور پڑ گیا کہ کفار مسلمان ہو گئے
ہیں.تو کفار نے کہا کہ ہم نے تو صرف اس لیے سجدہ کیا تھا کہ محمد رسول
اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم
نے اپنی تلاوت میں یہ فرمایا تھا کہ وتلك الغرانيق العلى وان شفاعتهن لترتجي
جس میں صاف طور پر ہمارے بتوں کو تسلیم کر لیا گیا تھا.پس جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے ہمارے بتوں
کو تسلیم کر لیا تو ہم نے بھی جواب میں اُن کے خدا کے آگے سجدہ کر دیا.جب
کفار کا یہ قول مشہور ہوا تو مفسرین کہتے ہیں کہ چونکہ حدیثوں سے ثابت ہے کہ اُس وقت کوئی
آواز آئی تھی جس میں یہ الفاظ سُنے گئے تھے کہ وتلك الــغـــرانيــق الـعـلــى وان
شفاعتهن لترتجی اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت کے یہی معنے ہیں کہ ہر نبی کی زبان
پر شیطان
کبھی کبھی خدائی منشاء کے خلاف الفاظ جاری کر دیتا تھا.لیکن اس آیت میں الفاظ جاری
کرنے کا کوئی ذکر نہیں بلکہ آیت کے صرف اتنے معنے ہیں کہ جب کوئی نبی دنیا میں کوئی خواہش
کرتا ہے اور نبی کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ دنیا کی اصلاح ہو جائے.اُس وقت شیطان جو اس
کی کامیابی کو نا پسند کرتا ہے اور اس کے راستہ میں روکیں ڈال دیتا ہے.القسی کے معنے ڈال
دینے کے ہوتے ہیں.پس الْقَى الشَّيْطَنُ فِی اُمُنِيَّتِہ کے یہی معنے ہیں کہ اُس کی خواہشوں
کے راستہ میں کوئی چیز ڈال دیتا ہے اور ظاہر ہے کہ شیطان روک ہی ڈالے گا نبی کی مددتو نہیں
کرے گا.پس ان الفاظ سے یہ معنے لینا کہ شیطان اس کی زبان پر شرکیہ الفاظ بھی جاری کر دیتا
ہے صریح ظلم ہے.مگر مشکل یہ ہے کہ اوپر کے بیان کردہ واقعہ کی روایت کو بڑے پایہ کے محدثین
نے صحیح تسلیم کیا ہے.چنانچہ ابن حجر جیسا محدث لکھتا ہے ان ثلاثة اسانيد منها على شرط
الصحيح ( فتح البیان) یعنی مختلف راویوں سے جو بڑے ثقہ تھے یہ روایت آتی ہے جن میں سے تین
روایتیں اتنی معتبر ہیں جتنی بخاری کی.اسی طرح بزاز اور طبرائی نے بھی اسے درست تسلیم کیا
Page 123
قرآن کریم میں تحریف کے الزامات کے جواب
107
ہے (ھمیان
الزاد ) جس کی وجہ سے ہم اس روایت کو کلی طور پر رد نہیں کر سکتے.لیکن خدا تعالیٰ نے اپنے فضل سے مجھے اس کا حل سمجھا دیا ہے جو یہ ہے کہ جب مسلمان
ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے تو مکہ والوں کو اُن کا حبشہ جانا بڑا بُر الگا اور اُنہوں نے اپنے بعض
آدمی نجاشی شاہ حبشہ کے پاس بھیجے کہ کسی طرح اُس کو سمجھا کر مہاجرین کو واپس مکہ لے آئیں
(سیرۃ الحلبیہ ) اور تاریخوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ جس وقت یہ سجدہ والا واقعہ ہوا.اس وقت کچھ
مہاجرین حبشہ سے لوٹ کر مکہ آگئے اور جب اُن سے لوگوں نے پوچھا کہ تم لوگ واپس کیوں
آگئے ہو تو انہوں نے کہا ہمیں تو یہ اطلاع پہنچی تھی کہ مکہ کے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں (ابن خلدون )
مکہ کے جو لوگ اُن سے ملے تھے انہوں نے کہا کہ مکہ والے تو کوئی مسلمان نہیں ہوئے.بات
یہ ہے کہ تمہارے رسول نے قرآن کی کچھ آیتیں سی پڑھی تھیں جن سے شرک کی تائید ہوتی تھی.اس لیے تمہارے رسول کے ساتھ مل کر مکہ والوں نے بھی سجدہ کر دیا مگر جبکہ بعد میں تمہارے
رسول نے ان آیتوں کو منسوخ قرار دے دیا تو مکہ والے پھر اپنے دین کی طرف لوٹ آئے.یہ
باتیں سُن کر وہ مہاجر پھر واپس حبشہ چلے گئے.(سیرۃ الحلبیہ )
سورہ نجم کی تلاوت کا واقعہ اور مسلمانوں کے حبشہ سے آنے کا واقعہ اتنا قریب قریب ہے کہ خود
جغرافیہ اس کو رڈ کرتا ہے.مکہ سے اس زمانہ کی بندرگاہ شعیہ کا فاصلہ اکیلے سوار کے لیے کم از کم چار
پانچ دن کا بنتا ہے.چنانچہ زرقانی میں لکھا ہے مسافتها طويلة جدا کہ مکہ سے شعیہ کا فاصلہ
بہت زیادہ ہے اور وہاں سے حبشہ کی بندرگاہ کا فاصلہ بھی کوئی چار پانچ دن
کا بنتا ہے.کیونکہ اس زمانہ
میں لوگ صرف بادبانی کشتیوں میں سفر کرتے تھے اور وہ بھی ہر وقت نہیں چلتی تھیں کیونکہ کوئی جہاز رانی
کی کمپنیاں نہیں ہوتی تھیں جب کسی ملاح کو فرصت ہوتی تھی وہ اپنی کشتی اُدھر لے آتا تھا جس میں
بعض دفعہ مہینوں کا فاصلہ ہو جاتا تھا اور حبشہ کی بندرگاہ سے لے کر اُس زمانہ کے حبشہ کے
دارالحکومت کا فاصلہ کوئی دو مہینہ کے سفر کا ہے.گویا اگر یہ خبرسورہ نجم کی تلاوت کے بعد مکہ سے جاتی
اور پھر مسلمان وہاں سے روانہ ہوتے تو مختلف فاصلوں اور دربار حبشہ کی اجازت وغیرہ کے زمانہ کو ملا
کر کوئی اڑہائی تین ماہ میں لوگ واپس آسکتے تھے.مگر وہ سجدہ والے واقعہ کے بعد پندرہ بیس دن کے
اندراندر واپس آگئے.کیونکہ مسلمان حبشہ جانے کے لیے رجب میں روانہ ہوئے تھے اور شعبان و
رمضان حبشہ میں ٹھہرے اور شوال میں واپس پہنچ گئے (زرقانی) اور حبشہ ٹھہر نے اور واپس مکہ پہنچنے کا
کل عرصہ تین ماہ سے بھی کم بنتا ہے (سیرۃ الحلبیہ ) اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ سورۃ نجم کی
تلاوت والا واقعہ بنایا گیا ہے یعنی بعض مکہ کے سرداروں نے پہلے سے یہ تدبیر سوچی اور کوئی سوار
یہ
Page 124
الذكر المحفوظ
108
حبشہ دوڑا دیا کہ مسلمانوں میں جا کر مشہور کر دو کہ مکہ کے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں اور انہوں نے
محمد رسول الله (ﷺ) کے ساتھ مل کر سجدہ کیا ہے.لیکن جب انہوں نے اندازہ کیا کہ اب حبشہ
والے آنے ہی والے ہوں گے تو سوچا کہ اُن کے آنے پر ہم کیا جواب دیں گے کیونکہ آکر وہ
دیکھیں گے کہ مکہ والے تو ابھی تک کافر ہیں اس لیے مشہور کر دیا کہ سجدہ کرنا ( نعوذ باللہ ) شرکیہ
آیتوں کی وجہ سے تھا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا ان آیتوں کو منسوخ کرنا جو در حقیقت
منسوخ کرنا نہ تھا بلکہ یہ اعلان کرنا تھا کہ ایسی کوئی آیتیں میں نے نہیں پڑھیں کفار مکہ کے واپس کفر
پر آجانے کی وجہ تھا.اب یہ تدبیر بھی کامیاب ہو سکتی تھی جبکہ کوئی شرکیہ آیتیں اس مجلس میں کہلائی
جاتیں جس میں آپ نے تلاوت
کی تھی.معلوم ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بلکہ
کسی خبیث کا فرنے اپنے سرداروں کے مشورہ سے پیچھے سے یہ فقرے پڑھ دیئے اور بوجہ اس کے
کہ سینکڑوں آدمی موجود تھے اور مکہ کے سارے رؤساء جمع تھے.شور میں پہچانا نہیں گیا کہ یہ آواز کس
کی ہے اور کفار نے مشہور کر دیا کہ چونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے یہ فقرے کہے ہیں
اس لیے ہم نے سجدہ کر دیا تھا.جو لوگ مجلس کے کناروں پر بیٹھے تھے انہوں نے بھی چونکہ یہ فقرے
اس مفتنی شیطان کے منہ سے سنے تھے.جس نے یہ فقرے آپ کی تلاوت کے وقت بآواز بلند کہہ
دیے تھے.اس لیے اُن لوگوں نے بھی یہ خیال کیا کہ شائد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ہی
یہ فقرے کہے ہوں.پس اس
کہانی کا حل تو یہ ہے کہ حمد رسول
اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی تلاوت
کے وقت کفار نے پہلے سے سوچے سمجھے ہوئے منصوبہ کے مطابق کسی خبیث سے یہ فقرے بلند
آواز سے کہلا دیے اور اُن کی سکیم کا ثبوت یہ ہے کہ مہاجرین حبشہ اسوقت سے پہلے مکہ پہنچ گئے جبکہ
سورہ نجم والے واقعہ کو سُن کر وہ ملکہ آسکتے تھے.بلکہ اگر اُسوقت ہوائی جہاز بھی ہوتے تو جتنے وقت
میں وہ آسکتے تھے.اُس سے بھی پہلے پہنچ گئے.پس اُن کا وقت سے پہلے مکہ آ جانا بتاتا ہے کہ وقت
سے پہلے اُن
کو کہلا بھیجا گیا تھا کہ مکہ والے مسلمان ہو گئے ہیں اور عین اُن دنوں میں جبکہ وہ سکیم کے
ماتحت آسکتے تھے مکہ والوں نے اوپر کے الفاظ کسی خبیث کے منہ سے بلند آواز سے کہلوا دیے.پھر اگر اُن حدیثوں کو نظر انداز کر دیا جائے جو صراحتاً قرآن کریم کے خلاف ہیں تو یہ سورۃ
ہی اس واقعہ کی تردید کرتی ہے کیونکہ ان آیتوں سے پہلے جن میں کہا گیا ہے کہ شیطان نے شرکیہ
مضمون ملا دیا تھا یہ ذکر ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے خدا کو دیکھا ہے بلکہ یہ بھی کہ
دودفعہ دیکھا ہے.چنانچہ پہلے فرمایا وَ لَقَدْ رَاهُ نَزَلَةً أخرى یعنی اُس نے یقینا اپنے خدا کو ایک
دفعہ اور دیکھا ہے اور پھر فرمایا لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبُری محمد رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
Page 125
قرآن کریم میں تحریف کے الزامات کے جواب
109
نے اپنے رب کے بڑے بڑے نشانات دیکھے ہیں اُس کے مقابلہ میں کافروں کو کہا گیا ہے کہ
أَفَرَتَيْتُمُ اللَّاتَ وَ الْعُزَّى یعنی بتاؤ تو سہی کہ کیا تم نے بھی محمد رسول
اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی
طرح اپنے بتوں کا کوئی نشان دیکھا ہے.یعنی تم نے نہیں دیکھا مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے اپنے خدا کے بڑے بڑے نشانات دیکھے ہیں.یہ تو شرکیہ آیات سے پہلے کی آیتیں اور ان
شرکیہ آیات کے بعد کی یہ آیت ہے کہ اِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاء سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَ آبَاؤُكُمْ مَا
أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطن یعنی یہ بتوں کے نام تو تم نے خود رکھ لیے ہیں.خدا تعالیٰ نے اس
کے لیے کوئی دلیل نہیں اُتاری.اب بتاؤ کہ کیا یہ ممکن ہے کہ شرک کے اقرار سے پہلے بھی شرک کی تردید کی آیتیں ہوں اور
اُن کے بعد بھی شرک کی تردید کی آیتیں ہوں.باوجود اس کے کوئی شخص کہہ دے کہ ان دو
تر دیدوں کے درمیان محمد صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی زبان پر شیطان نے شرک کے کلمات جاری
کر دیے تھے.شیطان کو تو ہمارے مفسر عقلمند کہتے ہیں.یہاں تک کہ سورہ بقرہ کی آیات میں
شیطان کو فرشتوں کا استاد قرار دیتے ہیں اور شیطان اور خدا تعالیٰ کے مباحثے میں خدا کو ہرایا گیا
ہے مگر اس کہانی والا شیطان تو کوئی گدھا معلوم ہوتا ہے کہ اُس کو شرکیہ کلمات کے لیے دو
زبر دست توحیدی آیات کے درمیان ہی مقام ملا.اس شیطان کو تو پاگل خانہ میں داخل کرنا
چاہیے.ایسا اتو خدا کے بندوں کو بہکا تا کس طرح ہے؟
پھر یہ لطیفہ دیکھو کہ یہ سورۃ اس آیت پر ختم ہوئی ہے فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا کہ اے لوگو اللہ
کے سامنے سجدہ کرو اور صرف اسی کی عبادت کرو.اس آیت کو سُن کر کون گدھا تھا جو یہ سمجھتا تھا کہ
محمد رسول اللہ نے کوئی شرکیہ کلمات کہ دیے ہیں.غرض اس سورۃ کی آیت آیت ہی اس کہانی کورد
کر رہی ہے.یہ اندرونی شہادت ہے اور بیرونی شہادت یہ ہے کہ مہاجرین حبشہ اس کہانی کوشن
کر اس وقت مکہ میں واپس نہیں آسکتے تھے جس وقت وہ آئے.جیسا کہ میں ثابت کر چکا ہوں.( تفسیر کبیر جلد ششم زیر آیت الحج 53 صفحہ 68 تا 71)
اب یہ واقعہ ہے شیطانی آیات کا اور یہ ہے اس کی حقیقت.اب بتائیں ابن وراق کہ کیا اعتراض ہے اس پر
اور کون سی آیات ہیں جو رسول کریم نے چھوڑی ہیں؟ پس جب ابن وراق کو واقعہ ہی غلط پہنچا ہے تو پھر نتیجہ بھی غلط
ہی ہے کہ یہ قصہ ظاہر کرتا ہے کہ رسول کریم نے کچھ آیات خرد برد کی ہیں“
اس مذکورہ بالا واقعہ کے علاوہ ایک واقعہ عبداللہ بن سعد ابی سرح کے حوالہ سے بھی پیش کیا جاتا ہے.مناسب
معلوم ہوتا ہے کہ اس واقعہ پر بھی ایک نظر ڈال لی جائے.
Page 126
الذكر المحفوظ
110
واقعہ عبد اللہ بن سعد ابی سرح
کتب تاریخ میں یہ ذکر ملتا ہے کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ سے پہلے یعنی مکی دور نبوت کے
کاتبین وحی میں سے ایک عبد اللہ بن سعد ابی سرح بھی تھے جو آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر نگرانی وحی قرآن کی
کتابت کے فرائض سرانجام دیا کرتے تھے.جب سورۃ المؤمنون کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں تو آنحضور نے
عبد اللہ بن ابی سرح کو یہ آیات تحریر کروائیں.لکھتے لکھتے جب آیت 15 میں اس مقام پر پہنچے جہاں اللہ تعالیٰ
فرماتا ہے ثُمَّ أَنشَأْنهُ خَلْقاً اخر تو عبد اللہ کے منہ سے بے اختیار نکلا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ اس
پر آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے یہی الفاظ تحریر کر دو جو ابھی تم نے کہے ہیں.اس پر وہ سمجھے کہ شائد
آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کلام الہی میں غیر اللہ کا کلام شامل کر دیتے ہیں اور اسلام سے برگشتہ ہو کر قریش مکہ سے جاملے.اس واقعہ کو مستشرق بہت اہمیت دیتے ہیں.ابنِ وراق نے بھی اس حوالہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر
اعتراض کیا ہے کہ آپ عبداللہ بن سعد ابی سرح شخص کے ساتھ مل کر قرآن کریم میں تبدیلیاں کیا کرتے تھے اور خوب
نمک مرچ لگا کر اس اعتراض کو اچھالا ہے.چنانچہ علی دانشی کی تے چاہتے ہوئے اس کے حوالہ سے ابنِ وراق کہتا ہے:
We also have the story of Abd Allah b.Sa'd Abi
Sarah.....the last named had for some time been one of
the scribes employed at Medina to write down the
revelations.On a number of occasions he had, with the
Prophet's consent, changed the closing words of verses.When the Prophet had said "And God is mighty and
wise," Abd Allah suggested writing down "knowing and
wise" and the Prophet answered that there was no
objection.Having observed a succession of changes of
this type, Abd Allah renounced Islam on the ground that
the revelation, if from God, could not be changed at the
prompting of a scribe such as himself.After his apostasy
he went to Mecca and joined the Qorayshites.(Why I Am Not A Muslim Page: 113,114)
عبداللہ بن سعد ابی سرح اُن کا تین میں سے تھے جنہیں مدینہ آکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم )
نے وحی لکھنے پر مقرر کیا تھا.کئی مواقع پر اس نے نبی (ﷺ) کی رضا ورغبت سے آیات کے
آواخر کو تبدیل کیا.نبی ﷺ کہتے کہ لکھو والله عـزیـز حکیم“ اور عبداللہ تجویز دیتا کہ
علیم حکیم اور نبی (ع) کہتے کہ ایسا لکھنے میں کوئی مضائقہ نہیں.عبداللہ بن ابی سرح.
Page 127
قرآن کریم میں تحریف کے الزامات کے جواب
111
نے اس وجہ سے کہ اگر یہ خدا کی وحی ہے تو میرے جیسا کوئی کا تب اسے کیونکر بدل سکتا.اسلام سے ارتداد اختیار کر لیا اور قریش کے ساتھ جا ملے.سب سے پہلے تو یہ امر پیش نظر رہے کہ واقعہ کی جو تفصیلات ابن وراق علی دانشی کے حوالہ سے بیان کر رہا ہے،
تاریخ اسلام کی کسی مستند کتاب میں ان کا ذکر نہیں ملتا.پس ابن وراق کا اعتراض تو یہیں دم تو ڑ دیتا ہے.عبد اللہ بن سعد ابی سرح مکی دور کے کاتب تھے جنہوں نے بعد میں ہجرت کی اور کچھ عرصہ بعد اسلام سے
روگردان ہو کر واپس مکہ آگئے.پس انہیں مدنی دور کا کاتب قرار دینا ابنِ وراق کی غلط بیانی ہے.شائد یہ دجل اس
لیے کر رہا ہے تا کہ قاری کے دل میں یہ تاثر پیدا ہو کہ مکہ میں کتابت وحی قرآن نہیں ہوا کرتی تھی اور یہ کہ ابن وراق
تو کہتا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت قرآن کریم کی کوئی تحریر موجود نہیں تھی.پھر کاتب وحی اور
وہ بھی مکی دور کا کہاں سے آ گیا ؟ مگر اس دجل میں شائد یہ بھول گیا کہ اس
کا دعوی تو یہ تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کے دور میں قرآن کریم کی کوئی تحریر سرے سے موجود ہی نہیں تھی.پس اپنے پاؤں پر خود ہی کلہاڑی مارلی.عبد اللہ بن ابی سرح کے واقعہ پر جب دیگر تاریخی حقائق کی روشنی میں اور اُس دور کے حالات کو مد نظر رکھ کر
نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس واقعہ میں تاریخی تضادات ہیں کیونکہ اول تو یہ روایت ہی قابلِ غور ہے
کہ جس میں بیان ہوا ہے کہ آپ آیت فَتَبَارَكَ اللَّه أَحْسَنُ الْخَالِقِینَ کی وجہ سے شک میں مبتلا ہو کر اسلام
سے روگردان ہو گئے تھے کیونکہ سورۃ المؤمنون مکی دور کے آخر میں غالباً بارہ نبوی کے لگ بھگ نازل ہوئی.ہجرت اس کے نزول کے بعد ہوئی ہے اور آپ بھی ہجرت کر کے مدینہ چلے آئے اور مدینہ آنے کے بعد آپ کو
اسلام کے بارہ میں شک پیدا ہوا ہے اور آپ واپس مکہ چلے گئے.پس فَتَبَارَكَ اللَّهِ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ کی
کتابت مکہ میں ہوئی اور اس وقت جو واقعہ ہوا وہ آپ کے شک اور اسلام سے روگردان ہونے کی بنیاد نہیں بنا بلکہ
اسوقت آپ ایمان پر قائم رہے اور ہجرت کی صعوبتیں برداشت کرتے ہوئے مدینہ میں اپنے آقا کے حضور حاضر
بھی ہوئے.پس تاریخی شواہد اس نتیجہ کو تقویت نہیں دیتے کہ آیت فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ کا آپ
کے دل کی آواز سے توارد وجہ ارتداد بنا اس لیے ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ آپ کے ارتداد کی وجہ کچھ اور
تھی.وجہ یہ آیت نہیں تھی بلکہ مدینہ آ کر کچھ ایسا ہوا ہے جس کی وجہ سے آپ اسلام سے روگردان ہوئے
ہیں.قرین قیاس ہے کہ اس روگردانی کی وجہ سیاسی ہے کیوں کہ آنحضور نے فتح مکہ کے وقت آپ کے قتل کا حکم دیا
تھا اور آنحضور نے جتنے لوگوں کے قتل کا حکم دیا تھا وہ سب سیاسی یا جنگی جرائم میں ملوث تھے.مذہبی اختلاف یا
ارتداد پر کسی کو سزائے موت نہیں دی.واللہ اعلم.فتح مکہ کے وقت عبد اللہ بن سعد ابی سرح نے تجدید بیعت کی
اور آپ کے بارہ میں ذکر ملتا ہے کہ حَسُنَ اسُلَامَهُ (اسد الغابه لابن اثیر: الجزء الثاني: تذكره عبد الله
Page 128
الذكر المحفوظ
112
بن سعد ابی سرح) یعنی آپ اسلام میں ترقی کرتے چلے گئے.یہ عام فہم حقیقت ہے کہ آنحضور کے ہمعصر مخالفین اسلام خوب چوکنے تھے اور اس تاک میں رہتے تھے کہ
کمزوری کا کوئی پہلو ہاتھ لگے.چنانچہ کسی بھی ایسے واقعہ کو انہوں نے اسلام کے خلاف ضرور استعمال کرنا تھا.پس
اگر عبداللہ بن ابی سرح در حقیقت اس طرح مرتد ہو کر واپس جاتے جس طرح ابن وراق کہہ رہا ہے تو مخالفین ضرور
شور کرتے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دین کی صداقت کو شبہ میں ڈالنے کے لیے اس واقعہ کو پیش
کرتے مگر اُن کی طرف سے حیرت انگیز خاموشی ہے اور نظر آتا ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ بھی اس واقعہ کو نہیں
اُچھالا بلکہ ایسے قرائن ملتے ہیں کہ گویا عبداللہ بن سعد ابی سرح کا واقعہ چھپایا جارہا ہے.اور نہ ہی صحابہ نہیں اس واقعہ
سے کوئی بے چینی پیدا ہوئی.صحابہ کے بارہ میں ہم گزشتہ میں دیکھ آئے ہیں کہ حفاظت قرآن کے بارہ میں ان کا
رویہ کس قدر حساس تھا.پس مخالفین اور صحابہ کی یہ پر اسرار خاموشی حق کو دعوت تحقیق دیتی ہے.مخالفین کی خاموشی کے ضمن میں ایک حیرت انگیز حقیقت یہ بھی ہے کہ عبد اللہ بن ابی سرح کے واقعہ کے بعد
ابوسفیان کا ہرقل کے دربار میں پیش ہونے کا واقعہ پیش آیا تھا.ہر قل نے پوچھا تھا کہ کیا اس نبی کے ماننے والوں
میں سے کبھی کوئی شخص مرتد بھی ہوا ؟ تو ابوسفیان نے جواب دیا نہیں! (بخاری کتاب بدء الوحي باب بدء الوحی)
اب ایک طرف تاریخ ذکر کرتی ہے کہ عبد اللہ بن ابی سرح مرتد ہوئے اور قریش سے جاملے اور دوسری طرف
ابوسفیان کہتا ہے کہ کوئی مرتد نہیں ہوا.ابوسفیان تو کہتا ہے کہ مجھے جھوٹ بولنے کا کوئی موقع ملتا تو اسلام کو اور
آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زک پہنچانے کے لیے میں ضرور بولتا مگر مجھے موقع نہیں ملا.جبکہ ادھر ایک واضح سچ کو
چھپا رہا تھا جو اسلام کے خلاف ایک مضبوط ہتھیار تھا اور جہاں ایک واضح موقع تھا اس سے بھی فائدہ نہیں اُٹھارہا اور
سراسر اعراض کر رہا ہے.اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عبداللہ بن سعد ابی سرح والے واقعہ کی نوعیت دراصل ویسی نہیں
جیسا کہ ابن وراق نے نقل کیا ہے.اگر در حقیقت عبد اللہ نے یہ واقعات بیان کیے ہوتے جو ابنِ وراق ان کی طرف
منسوب
کر رہا ہے تو مخالفین کے ہاتھ اسلام کے خلاف ایک بہت زبردست ہتھیار آجاتا کیونکہ عبداللہ بن سعد ابی سرح
تو اس درجہ با صلاحیت آدمی تھے کہ بعد میں جب مسلمان ہوئے تو حضرت عثمان کے زمانہ میں مصر کے گورنر رہے نیز
شمالی افریقہ کے بہت سے علاقے مصر تونس الجزائر وغیرہ آپ کے ہاتھوں فتح ہوئے.امیر معاویہ کے ساتھ مل کر
اسلامی بحری بیڑے کی شان و شوکت میں اضافہ کیا.فلپ کے حتی آپ کے بارہ میں لکھتے ہیں:
"His greatest performance was his part in the
establishment of the first Moslem fleet.....In Muaviyah
and Abdullah Islam developed its first two admirals."
(History of the Arabs Page: 167)
یعنی مسلمانوں کا بحری بیڑہ بنانا ان کا عظیم کارنامہ ہے.امیر معاویہ اور عبد اللہ کی شکل میں
Page 129
قرآن کریم میں تحریف کے الزامات کے جواب
اسلام کو پہلے دو امیرالبحر ملے.113
پس آپ
کا یہ کہنا کہ میں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی رضا مندی سے قرآن کریم میں رد و بدل کر دیا کرتا تھا، ایسا
غیر اہم واقعہ نہیں تھا کہ کفار خاموش رہتے اور ابوسفیان آپ کے مرتد ہونے اور ان تفصیلات کو کوئی اہمیت ہی نہ دیتا.عبداللہ بن سعد ابی سرح تو مکی دور کے کاتب تھے.تاریخ میں مدنی دور کے ایک واقعہ کا ذکر ملتا ہے.روایت ہے:
أن رجلا كان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا املى عليه
سميـعــا يـقـول كتبت به بصيرا، قال دعه واذا املى عليه عليما حكيما
كتب عليما حليما - قال : وقد كان قرأ البقرة وآل عمران و كان قرأهما
قد قرأ قـرانـاً كثيرا فذهب متنصرا فقال لقد كنت اكتب لمحمد ما
شئت فيقول: دعه فمات فدفن فنبذته الارض مرتين او ثلاثا قال ابو
طلحه ولقد رأيته منبوذا فوق الارض.(مسند احمد بن حنبل الجزء الرابع، مسند انس بن مالك 3/246 كتاب المصاحف
باب من كتب الوحى لرسول الله الا
الله)
یعنی ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی قرآن کی کتابت کیا کرتا تھا.آپ اُسے
لکھواتے سمیعا تو وہ بصیرا لکھ دیتا.آپ نے فرمایا جانے دو.اسی طرح جب آپ اُسے
لکھواتے علیما حكيما تو وہ لکھتا عليما حليما اس پر بھی آپ نے فرمایا کہ جانے دو.اس
نے سورۃ البقرۃ اور سورۃ ال عمران ، قرآن کریم کا ایک بڑا حصہ حفظ کیا ہوا تھا.وہ کچھ عرصہ بعد
عیسائی ہو گیا اور جگہ جگہ یہ کہتا پھرتا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ لکھواتے تھے اور
میں کچھ اور لکھا کرتا تھا.اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تعرض نہ کرتے.اس کی موت کے
بعد جب اُسے دفناتے تو زمین اس کی لاش اُگل دیتی اور ایسا دو، تین مرتبہ ہوا.ابوطلحہ فرماتے
ہیں کہ میں نے اس کی لاش سطح زمین پر
گلتی سڑتی دیکھی تھی.مذکورہ بالا روایت میں جو تفصیلات بیان کی گئی ہیں، ابن وراق انہیں عبد اللہ بن سعد ابی سرح کی طرف
منسوب کر رہا ہے.جبکہ روایت میں واضح ذکر ہے کہ یہ شخص مدینہ کا تھا، مدینہ میں ہی وحی لکھا کرتا تھا اور مدینہ میں
ہی مرا تھا.نہ تو اس نے مکہ سے ہجرت کی تھی اور نہ ہی مرتد ہو کر کبھی مکہ گیا تھا.جبکہ عبداللہ بن سعد ابی سرح مکی دور
کے کاتب تھے.ہجرت کر کے مدینہ آئے اور جلد ہی واپس چلے گئے تھے.پس ابنِ وراق کے پیش کردہ علی داشتی
کے حوالہ میں اس شخص کو عبداللہ بن ابی سرح کا نام دیا گیا ہے جو کہ سراسر غلط ہے.مذکورہ بالا روایت میں مذکور شخص کا ذکر حضرت امام بخاری اپنی صحیح میں بھی کرتے ہیں.مگر ظاہر ہے کہ اس
Page 130
الذكر المحفوظ
114
زیادہ مستند روایت میں بیان تفصیلات ابنِ وراق کے کسی کام کی نہیں اس لیے ان سے اعراض کرتے ہوئے اپنے
اعتراض کی بنیاد نسبتا کمز ور روایت پر رکھتا ہے جیسا کہ مستشرقین کا عام وطیرہ ہے.ابن وراق بخاری کی روایت
اس لیے درج نہیں کرتا کیونکہ اس میں واضح طور پر درج ہے کہ یہ شخص جو بھی تھا مرتد ہونے کے بعد ایسی باتیں کیا
کرتا تھا.جبکہ ابن وراق نے جو نسبتا کم درجہ استناد کی حامل روایت چچنی ہے اور اُسے بھی مسخ کر کے پیش کیا ہے
اس روایت کا راوی یہ بات کر رہا ہے نہ کہ مرتد ہونے والا شخص.بخاری کی شرح فتح الباری میں اس شخص کے بارہ میں یہ وضاحت ملتی ہے کہ اس کا نام معلوم نہیں لیکن وہ
حضرت انسؓ کے قبیلہ بنی نجار میں سے تھا اور عیسائی تھا.آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ کے بعد مسلمان
ہوا اور کچھ عرصہ بعد مرتد ہو کر پھر عیسائی ہو گیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی مر گیا.(فتح الباری
كتاب المناقب باب علامات النبوة) جبکہ عبداللہ بن سعد ابی سرح قریش مکہ میں سے تھے اور آنحضور نے کی
وفات کے بعد لمبا عرصہ زندہ رہے اور اسلام کی قابل قدرخدمات کی سعادت پائی.بخاری کی روایت کے مطابق یہ شخص مرتد ہونے کے بعد کہتا پھرتا تھا کہ میں اپنی مرضی سے وحی قرآن کے الفاظ بدل
دیا کرتا تھا.اب واضح سی بات ہے کہ جب ایک شخص مرتد ہو گیا ہے تو پھر عین ممکن ہے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
اور اسلام کے بارہ میں مخالفت کے جوش میں جھوٹ بھی بولے.عقلِ سلیم یہی گواہی دیتی ہے کہ وہ جھوٹ ہی بولا کرتا
تھا.کیونکہ صحابہ خانمونہ تو ہم دیکھ آئے ہیں کہ قرآن کریم کے بارہ میں کس قدر حساس تھا.تلاوت کے وقت عربی زبان
کے ادنی سے قبائلی فرق پر بھی صحابہ ایسے شخص کو گردن سے پکڑ کر آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیتے
تھے.حالانکہ یہ فرق در حقیقت کوئی اختلاف نہیں تھا بلکہ الہی اجازت سے آسانی پیدا کرنے کی خاطر اٹھایا گیا ایک
قدم تھا.پس اس کو تو صحابہ برداشت نہیں کرتے کجا یہ کہ ایک شخص آیات کے آواخر بدل دے اور صحابہ خاموش رہیں.ایک قابل غور بات یہ ہے کہ فتح مکہ کے وقت آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد اللہ بن سعد ابی سرح کے قتل کا
حکم جاری کیا ہوا تھا.اب اگر اس کے مرتد ہونے کی وجہ یہی تھی جو ابن وراق بیان کر رہا ہے تو پھر بنی نجار کے
عیسائی کے بارہ میں بھی یہی حکم جاری کیا جانا چاہیے تھا.خاص کر جب کہ تاریخ میں واضح ذکر ہے کہ اس نے
الزام تراشی میں عبداللہ بن سعد ابی سرح سے بہت زیادہ مبالغہ آرائی کی تھی.مگر آنحضور نے اس کے قتل کا حکم
جاری نہ کیا بلکہ اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا.بنی نجار کے عیسائی کے قتل کا حکم جاری نہ کرتا اورعبد اللہ بن ابی سرح
کے قتل کا حکم دینا بتا تا ہے کہ دونوں کے مرتد ہونے کی وجہ مختلف تھی.فتح مکہ کے بعد آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
جن لوگوں کے بھی قتل کا حکم دیا ان سب کے پیچھے وجوہات سیاسی تھیں اور وہ سب لوگ جنگی جرائم کے مرتکب تھے
نہ کہ اُن کا مرتد ہونا اُن کی سزائے موت کی وجہ تھا.عبد اللہ بن سعد ابی سرح بھی انہی میں سے ایک تھا.پس اس
Page 131
قرآن کریم میں تحریف کے الزامات کے جواب
کے مرتد ہونے کی وجہ بھی سیاسی ہی تھی.واللہ اعلم.115
پس روایات کے تجزیہ سے واضح ہو جاتا ہے کہ عبداللہ بن سعد ابی سرح کے واقعہ کو اس شخص کے واقعہ سے خلط ملط
کر دیا گیا ہے.تفصیلات اس شخص کی لی گئی ہیں جو بعد میں عیسائی ہو گیا تھا اور نام عبداللہ بن سعد ابی سرح کالیا گیا ہے.اور قابل غور بات یہ ہے کہ مدنی دور میں مرتد ہونے والے اس شخص کے بارہ میں بھی آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم
کے دور کے مخالفین اسلام پر اسرار طور پر خاموش ہیں.نیز یہ بات بھی قابل غور ہے کہ ایک شخص اتنا واضح انداز
میں ذکر کرتا ہے کہ وہ ایسا کیا کرتا تھا اور آنحضور صل اللہ علیہ وسلم بھی اور صحابہ کرام بھی اسے کچھ اہمیت نہیں دیتے.معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص بھی ابن وراق کی طرح عیسائیت کا ایک دجل تھا اور ایسا بھونڈا دجل تھا کہ رسول کریم صلی
اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ پر اس کی حقیقت آشکار ہو ہی چکی تھی.اور اس کے ساتھ ساتھ مخالفین کو بھی اس کا
طریقہ واردات کچھ ایسا نہ بھایا کہ اسے وقعت دیتے یا پھر یہ کہ اس شخص کا کردار ایسا تھا کہ دوست اور دشمن سب
اس کی بات کو اہمیت نہیں دے سکتے تھے اور اس کی اتنی حیثیت نہیں تھی یا اس کا جھوٹا ہونا اتنا مسلم تھا کہ مخالفین بھی
اُسے اسلام کے خلاف بطور گواہ پیش کرتے ہوئے ہچکچاتے اور خاموشی میں ہی عافیت سمجھتے تھے.واللہ اعلم.دوسری طرف عبد اللہ بن سعد ابی سرح کا واقعہ بھی قطع نظر اپنی جملہ تفصیلات کے، ہمعصر مخالفین کی طرف سے
کبھی اچھالا نہیں گیا.حالانکہ عبداللہ بن سعد ابی سرح تو اس مقام اور مرتبہ کے انسان تھے کہ اگر ان کی طرف سے
حفاظت قرآن کے سلسلہ میں کوئی الزام لگتا تو ایک شور مچ جاتا مگر اس حوالہ سے مخالفین کے کیمپ میں مکمل خاموشی
رہی.لیکن اب
تلبیس یہ کی گئی کہ عبداللہ بن سعد ابی سرح کے حوالہ سے وہ کچھ کہا گیا جو مدنی دور میں عیسائی ہوکر
مر جانے والا شخص کہا کرتا تھا.چنانچہ جب شخصیت تبدیل ہوئی تو واقعہ اہم ہو گیا.گویا اُس عیسائی ہونے والے
شخص کی بات کی کوئی اہمیت نہیں تھی مگر اب جب یہ دجل کیا گیا کہ اُس شخص کی بات کو عبد اللہ بن سعد ابی سرح کی.شخصیت کے سائے میں پیش کیا گیا تو شخصیت معتبر ہوگئی اور نتیجہ تفصیلات بھی اہم ہو گئیں.پس جب اُس دور کے ہمعصر مخالفین اسلام ان دونوں واقعات کو غیر اہم سمجھتے ہیں اور انہیں ان واقعات میں
اسلام کے خلاف کوئی ثبوت نظر نہیں آتا تو آج پندرہ سو سال گزر جانے کے بعد ان واقعات کی بنیاد پر کیونکر
اعتراض کیا جاسکتا ہے؟ ان واقعات کو مسخ کر کے اعتراض کی صورت میں پیش کرنا دجل وفریب کے سوا کچھ نہیں.عبد الله بن سعد ابی سرح کے واقعہ کے غلط یا صحیح ہونے سے قطع نظر ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ بعض اوقات نبی
پر نازل ہونے والی وحی الہی کا پر تو اور لوگوں پر بھی پڑ جاتا ہے.سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیونکر ہوتا ہے؟ تو اس
سلسلہ میں عرض ہے کہ یہ امراہل علم پر مخفی نہیں کہ نبی کے وقت انتشار نورانیت ہوتا ہے اور نبی پر نازل ہونے والی
وحی کا پر تو سعید فطرت لوگوں پر بھی پڑتا ہے.اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی
بخش تحریرات سے روشنی حاصل کرتے ہیں.آپ فرماتے ہیں:
Page 132
الذكر المحفوظ
116
یہ بات بھی یادر ہے کہ زمانہ کے فساد کے وقت جب کوئی مصلح آتا ہے اس کے ظہور کے
وقت پر آسمان سے ایک انتشار نورانیت ہوتا ہے.یعنی اس کے ساتھ زمین پر ایک نور بھی اترتا
ہے اور مستعد دلوں پر نازل ہوتا ہے تب دنیا خود بخو د بشرط استعداد نیکی اور سعادت کے طریقوں
کی طرف رغبت کرتی ہے اور ہر یک دل تحقیق اور تدقیق کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور نامعلوم
اسباب سے طلب حق کے لئے ہر یک طلب حق کے لئے ہر یک طبیعت مستعدہ میں ایک حرکت
پیدا ہو جاتی ہے غرض ایک ایسی ہوا چلتی ہے جو مستعد دلوں کو آخرت کی طرف ہلا دیتی ہے اور
سوئی ہوئی قوتوں کو جگا دیتی ہے اور زمانہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا ایک انقلاب عظیم کی طرف
حرکت کر رہا ہے سو یہ علامتیں اس بات پر شاہد ہوتی ہیں کہ وہ مصلح دنیا میں پیدا ہوگیا پھر جس قدر
آنے والا مصلح عظیم الشان ہو یہ غیبی تحریکات اسی قوت سے مستعد دلوں میں اپنا کام کرتی ہیں.ہر یک سعید الفطرت جاگ اٹھتا ہے اور نہیں جانتا ہے کہ اس کو کس نے جگایا.ہر یک صحیح الجبلت
اپنے اندر ایک تبدیلی پاتا ہے اور انہیں معلوم کر سکتا کہ یہ تبدیلی کیونکر پیدا ہوئی.فرض ایک جنبش
سی دلوں میں شروع ہو جاتی ہے اور نادان خیال کرتے ہیں کہ یہ جنبش خود بخود پیدا ہوگئی لیکن
در پردہ ایک رسول یا مجدد کے ساتھ یہ انوار نازل ہوتے ہیں چنانچہ قرآن کریم اور احادیث کی
رو سے یہ امر نہایت انکشاف کے ساتھ ثابت ہے.“
دوسری جگہ فرماتے ہیں:
شہادت القرآن، روحانی خزائن جلد 6 صفحہ 312,313)
سو ملائکہ اور روح القدس کی تنزیل یعنی آسمان سے اتر نا اُسی وقت ہوتا ہے جب ایک
عظیم الشان آدمی خلعت خلافت پہن کر اور کلام الہی سے شرف پر کر زمین پر نزول فرماتا ہے
روح القدس خاص طور اس خلیفہ کو ملتی ہے اور جو اس کے ساتھ ملائکہ ہیں وہ تمام دنیا کے مستعد
دلوں پر نازل کئے جاتے ہیں.تب دنیا میں جہاں جہاں جو ہر قابل پائے جاتے ہیں سب پر
اُس نور کا پر تو پڑتا ہے اور تمام عالم میں ایک نورانیت پھیل جاتی ہے اور فرشتوں کی پاک تاثیر
سے خود بخود دلوں میں نیک خیال پیدا ہونے لگتے ہیں.“
فتح اسلام روحانی خزائن جلد 3 حاشیہ صفحہ 12 )
اسی طرح ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ قرآن کریم کا دعوی ہے کہ اس کی تعلیم انسانی فطرت کے عین مطابق
ہے.چنانچہ جو کچھ قرآن کریم میں بیان ہے ہر سعید فطرت روح اسے تسلیم کرے گی.اور جو جتنا سعید فطرت ہوگا
Page 133
قرآن کریم میں تحریف کے الزامات کے جواب
117
اتناہی اس کا دل قرآنی تعلیم سے مشابہ ہوگا.چنانچہ یہ واقعہ اور بہت سے دیگر واقعات اس دعوی کی صداقت میں
دوسرے دلائل کے علاوہ ایک پختہ دلیل ہیں.چنانچہ منافقین کا جنازہ پڑھنے سے ممانعت،احکام حجاب کا نزول،
مقام ابراہیم کومصلی بنانا وغیرہ مضامین پر مشتمل آیات قرآن کریم کی تعلیم کے سعید انسانی فطرت کے عین مطابق
ہونے کی دلیل کے طور پر بطور تعلیم قرآن کریم میں نازل ہوئیں.علاوہ ازیں آیت فَتَبَارَكَ الله أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ اس سے قبل بیان ہونے والے مضمون کا ایک طبعی نتیجہ
ہے.لطف کی بات یہ ہے کہ صرف عبد اللہ بن سعد ابی سرح کی ہی زبان پر یہ آیت جاری نہیں ہوئی بلکہ مدینہ آکر
جب آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ المؤمنون کی ہی آیات حضرت زید بن ثابت کو لکھوائیں تو یہی آیت
دوسرے صحابہ کی زبان پر بھی جاری ہوئی.حضرت زید بن ثابت روایت کرتے ہیں کہ:
وو
املى على رسول الله لا ل
له هذه الآية " وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ
طِينِ» الى ” فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ “ فقال معاذ بن جبل ” فَتَبَارَكَ
اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، فضحك رسول الله الا
الله فقال له معاذ بم ضحكت يا
رسول الله، قال بم ختمت.فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ “
66
(حافظ طبرانی: المعجم الاوسط ،متوفى سنه 360 جلد 5 حديث 4654)
حضرت زید فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سورۃ المؤمنون کی آیات
وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ سے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ تِک
املا کر وا ر ہے تھے تو معاذ بن جبل بے اختیار بول اُٹھے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ -
اس پر رسول اللہ اللہ ہنس دیے.معاذ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول آپ کیوں ہنسے تو آپ
نے فرمایا تمہارے فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ کہنے پر ( کیونکہ یہ بھی وحی کا حصہ ہے ).ایک اور جگہ بھی یہ روایت ملتی ہے کہ جب حضرت عمر نے سورۃ المؤمنون کے آیات ثُمَّ أَنشَأْنَهُ خَلْقاً
اخر تک سُنیں تو آپ کے دل سے بھی بے اختیار یہی صدا بلند ہوئی فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ.(حافظ طبرانی : المعجم الاوسط متوفى سنه 360 جلد 6 حديث 5658)
اب یہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر دیگر صحابہ کے دل کی آواز گواہ ہوگئی کہ یہ رسول کریم صلی
اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی سے متن قرآن میں درج نہیں کروائی بلکہ وحی الہی تھی.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کے بننے میں ایک حکمت یہ بھی ہوگی کہ عبد اللہ بن سعد ابی سرح کے بعد مزید ایک گواہی مل گئی کہ یہ آیت اپنے
مضمون کی حسنِ ترتیب کی وجہ سے ثُمَّ أَنشَأْنَهُ خَلْقاً اخر تک مضمون سننے کے بعد پاک طینت سامع کے دل
سے خود بخودہی پھوٹ پڑتی ہے.
Page 134
الذكر المحفوظ
118
علامہ آلوسی اس حقیقت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:
ان ذلك من حسن نظم القرآن الكريم حيث تدل صدور كثير من آياته
(علامه محمود آلوسی : روح المعانی جلد 10 صفحه 16 تفسير سورة المؤمنون
آيت فتبارك الله احسن الخالقين)
یعنی یہ آیت یقیناً قرآن کریم کے حسنِ ترتیب کی بہترین مثال ہے کہ قرآن کریم کی آیات
کے اعجاز پر بہت سے لوگوں کے دل گواہی دیتے ہیں.خلاصہ
عبد اللہ بن سعد ابی سرح کا واقعہ ایک دوسرے شخص کے واقعہ سے خلط ملط کر کے پیش کیا گیا ہے.اس واقعہ
سے ایسا کوئی ثبوت اُس دور کے مخالفین کے ہاتھ نہیں لگا کہ وہ اسے اسلام کے خلاف استعمال کر سکتے.اس طرح
دوسرا شخص جو کوئی بھی تھا وہ اس قابل نہیں تھا کہ مخالفین اسے اسلام یا قرآن کے بارہ میں شکوک پیدا کرنے کے لیے
بطور گواہ استعمال کر سکتے.پس یہ دونوں واقعات اُس دور کے مخالفین اسلام کے نزدیک اسلام کے خلاف کسی قسم کا
کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکے اور نہ ہی جائے اعتراض تھے.اعتراض پیدا کرنے کے لیے روایات کو خلط ملط کر کے
اُس شخص کے واقعہ کو عبد اللہ بن سعد ابی سرح کے حوالہ سے پیش کر کے عدل وانصاف کا خون کیا گیا.نیز یہ بھی
مد نظر رہے کہ از روئے تاریخ عبد اللہ بن سعد ابی سرح کے اسلام سے روگرداں ہونے کی وجہ کتابت قرآن نہ تھی.جہاں تک عبداللہ بن ابی سرح کے وحی الہی سے تو اردو کا تعلق ہے تو یہ جائے اعتراض نہیں کیونکہ نبی الزمان کی
آمد کے وقت انتشار نورانیت ہوتا ہے اور سعید فطرت لوگوں کو بھی خدا تعالیٰ ایمان کی پختگی کے لیے نبی پر نازل
ہونے والی وحی الہی سے کچھ حد تک سرفراز کر دیتا ہے.علاوہ ازیں یہ کہ قرآن کریم کی آیات میں خاص ربط ہے جو انسانی فطرت کے عین مطابق ہے.پس انسانی
فطرت سے جو آواز اُٹھتی ہے اسے قرآن کریم نے نہایت حسین اور دلکش پیرایہ میں الفاظ کا جامہ پہنایا ہے.یہ آواز
مختلف مواقع پر بعض دیگر صحابہ کے دلوں سے بھی اٹھی اور عبداللہ بن سعد ابی سرح کے دل سے بھی وہی آواز اٹھی.اسی فطرتی سعادت کی وجہ سے آپ نے دوبارہ آغوش اسلام میں آن پناہ لی اور صحابہ کے نقوشِ پا پر چلتے ہوئے اپنی
زندگی اسلام کی خدمت کے لیے وقف کر دی اور بیچے جانثار اور خدمت گزار دین بن کر زندگی گزاری.ان دو واقعات کو خلط ملط کر کے ابن وراق یہ شبہ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نے قرآن کریم میں ردو بدل کیا ہے.اب جب واقعات کی حقیقت تو قاری پر کھل ہی چکی ہے.اب ان واقعات
کو غلط انداز میں پیش کر کے جو غلط نتیجہ نکال رہا ہے اس پر بھی نظر ڈالتے ہیں کہ کیا ایسا سوچا بھی جاسکتا ہے؟
Page 135
قرآن کریم میں تحریف کے الزامات کے جواب
119
رسول کریم اللہ قرآن کریم میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتے تھے
ابن وراق نے متنازعہ آیات اور عبد اللہ بن سعد ابی سرح کے واقعات کو تاریخی طور پر مسخ کر کے پیش کر کے
قاری کے ذہن میں یہ شبہ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے کہ (معاذ اللہ ) رسول معصوم و صادق و امین صلی اللہ علیہ
وسلم بھی قابل اعتبار نہیں تھے اور ہو سکتا ہے کہ آپ نے حالات کے مطابق کچھ رڈو بدل کیا ہو.کیونکہ یہ تو ثابت
ہو گیا اور اس بات میں بھی کوئی شک کی گنجائش نہیں کہ قرآن کریم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور
حفاظت کے تمام ظاہری تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ہم تک پہنچا لیکن یہ اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ جو خدا
نے نازل کیا ہے وہی ہم تک پہنچا ہے.کیا ایسا ممکن نہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے اس میں خود ہی
کوئی رد و بدل کر دیا ہو؟ وسیلیم میور بھی ایک جگہ قرآن کی بے نظیر حفاظت کا اعتراف کرتے ہوئے ساتھ ہی ان
الفاظ میں نیش زنی بھی کر جاتا ہے کہ :
"What we have, though possibly created and
modified by himself, is still his own."
ترجمہ.اب جو قرآن ہمارے ہاتھوں میں ہے.گو یہ بالکل ممکن ہے کہ محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم) نے اپنے زمانہ میں اسے خود بنایا ہو اور بعض دفعہ اس میں خود ہی بعض تبدیلیاں بھی کر دی
ہوں مگر اس میں شبہ نہیں کہ یہ وہی قرآن ہے جو محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ) نے ہمیں دیا تھا.آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارہ میں یہ کہنا کہ ہو سکتا ہے آپ نے قرآن کریم میں اپنی طرف سے کچھ
رڈو بدل کیا ہو اس کے جواب میں اول تو یہ کہنا ہی کافی ہے کہ یہ صرف ایک شک یا صرف ایک دعوی ہے جو کہ
ثبوت کے ساتھ پیش کرنا چاہیے کہ واقعی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم میں کوئی رد و بدل کیا ہے.جو دو
واقعات تم نے پیش کیے ہیں وہ تاریخ حقائق کی روشنی میں غلط ثابت ہوتے ہیں.پس اگر کوئی ثبوت نہیں ہے تو
پھر ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ یہ شک غلط اور بے بنیاد ہے اور شک کرنے والے کی اندرونی غلاظتوں کا ایک
نمونہ ہے.این وراق کی طرح مذکورہ بالا سطور میں ویلیم میور نے بھی سراسر ظلم کی راہ اپنائی ہے.تاریخ کا مطالعہ
کرنے کے بعد یہ تو تسلیم کرلیا کہ رسول کریم کے صحابہ نے کمال دیانت داری اور عشق و وفا کے بے نظیر نظارے
دکھاتے ہوئے قرآن کریم بلا کم و کاست ہم تک پہنچایا.مگر اُن صحابہ کے آقا ومطاع، جن کی تربیت نے صحابہ کو
دیانت داری کے یہ اعلیٰ اسلوب دکھائے اور اپنے مولیٰ سے ایسی محبت سکھائی جس کو بنیاد بناتے ہوئے انہوں
نے قرآن کریم کا بحیثیت کلام الہی غیر معمولی اکرام کیا اور اپنی جانیں نچھاور کر کے اس کی حفاظت کی ، اُس مربی اعظم
پر بلا ثبوت اعتراض کر دیتا ہے.کیا جو نمونہ صحابہ نے محافظت قرآن کے ضمن میں دکھا یا وہ اُن کا آقا نہیں دکھا سکتا
Page 136
الذكر المحفوظ
120
تھا ؟ کیا حضرت عیسی کے اس قول پر ویلیم میور کو ایمان نہیں کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے.“؟
جب صحابہ کے اخلاق کی شان ایسی بلند تھی تو پھر ان کے آقا کی شان بلند تو وہم و گمان سے برتر ہے.پھر لطف یہ کہ
دوسری جگہ خود ہی اپنے اس قول کو ر ڈ بھی کر دیتا ہے جہاں یہ گواہی دیتا ہے کہ:
"Our authorities all agree in ascribing to the youth of
Mohammad a modesty of deportment and purity of
manners rare among the People of Mecca...and he
received the title, by common consent, of Al-Ameen, the
Trustworthy."
(W.Muir:Life of Mohammad, London 1903.Intorduction pg17)
ہماری تمام تر تحقیقات اس معاملہ میں متفق ہیں کہ محمد (ﷺ) کی جوانی تو ازن اور پاکیزگی
کا شاہکار تھی جو اس دور کے عربوں میں مفقود تھا.آپ کو خطاب ملا تھا الا مین!
سب سے بڑھ کر قابل اعتماد
دُنیا کی عام عدالتوں میں بھی اگر کسی پر کسی جرم کا مقدمہ بنایا جائے تو باوجود اس کے کہ ملزم کی عصمت اور
پاک دامنی کوئی ثابت شدہ امر نہیں ہوتا اور نہ ہی دوست دشمن کا اس پر اتفاق ہوتا ہے کہ یہ شخص ایسے اعلیٰ اخلاقی
مرتبہ و مقام کا ہے کہ اس سے ایسا جرم سرزد ہونا محال ہے.بلکہ اگر جانتے بھی ہوں کہ یہ شخص اس قماش کا ہے کہ
اس سے غلط حرکت یا جرم سرزد ہونا بعید از قیاس نہیں ہے تو پھر بھی مقدمہ قائم کرنے والے سے ثبوت طلب کیا جاتا ہے
اور تسلی بخش ثبوت مہیا نہ کر سکنے پر اس ملزم کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جاتی.بلکہ ثبوت مہیا نہ ہونے پر عدالت
ملزم کو یہ حق بھی دیتی ہے کہ ایسا مقدمہ قائم کرنے والے یعنی مدعی کے خلاف ہتک عزت اور ہرجانہ کا دعوی بھی کرے.اگر ایسا نہ کیا جائے تو دُنیا میں بدباطن اور گندے دل و دماغ والے لوگ شرفاء کا جینا حرام کر دیں.ہر بے شرم جسے
جھوٹ بولنے سے صرف سزا کا خوف ہی روک سکتا ہے، کھل کر اپنی غلاظتوں سے معاشرہ کو خراب کرتا چلا جائے.قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :
ط
وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنَّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا (يونس: 37)
اور اُن میں سے اکثر ظن کی پیروی کرتے ہیں اور حتمی بات کے مقابل پر اندازوں کی تو کوئی
اہمیت نہیں ہوسکتی.یہ ایک حقیقت ہے کہ ایک مہذب معاشرہ میں کسی عام شخص پر بھی بلا ثبوت جھوٹ کا الزام لگا نائر افعل سمجھا
جاتا ہے بلکہ اشتہاری مجرموں پر بھی اگر کوئی نئی فرد جرم لگائی جائے تو بھی ثبوت پیش کرنا ضروری ہوتا ہے.پھر انبیاء، جن کی پاک دامنی پر ہم عصر مخالف اور موافق گواہ ہوتے ہیں.جان کے دشمن بھی ان کے اعلیٰ
اخلاق کی گواہی دیتے ہیں.کروڑ ہا بندگان خدا ان کا اسوہ اپنی زندگیوں میں بطور اخلاق کے اپناتے ہیں اور
Page 137
قرآن کریم میں تحریف کے الزامات کے جواب
121
ان پاکیزہ ہستیوں کی عشق و محبت سے اپنی زندگی کا سامان کر رہے ہوتے ہیں.ان پاکیزہ ہستیوں کے بارہ
میں بلا ثبوت اس امر کے کہ انہوں نے کسی کے سامنے مسودہ میں کوئی تحریف کی ہو یا مسودہ بناتے ہوئے کسی
سے مدد لی ہو یا کسی کو اس امر میں اپنا راز دان بنایا ہو یا کبھی موت جیسی تکلیف سامنے دیکھ کر خود ہی اپنے جرم کا
اعتراف کر لیا ہو، فوراً تہمت لگانے پر تیار ہو جانا اور ہزاروں گواہیوں کے مقابل پر عدم علم کو بنیاد بنا کر، بیہودہ
اندازے لگاتے ہوئے حقیقت کو ر ڈ کر دینا کہاں کی علمیت اور تنقیدی تحقیق ہے.اس رویہ کو تو خود دیانت دار
محققین نا پسند کرتے ہیں اور اسے تنقید کا نشانہ بناتے ہیں.چنانچہ ممتاز مستشرق Jeffery Lang اور کیرم
آرمسٹرانگ اس بارہ میں وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مستشرقین ایک طرف تو احادیث کو قابل
اعتراض ٹھہراتے ہیں اور پھر خود ہی ان میں سے مستند روایات کو چھوڑ کر غیر مستند حصہ کو اپناتے ہیں اور اس پر
اپنے غلط اندازوں کی بنیادرکھتے ہیں اور اسلام اور قرآن مجید پر اعتراض کرتے ہوئے خود اپنے ہی مسلّمہ
قوانین کو جھٹلا دیتے ہیں.انہیں خیالات کا اظہار ممتاز مستشرق Edward Said نے بھی کیا ہے:
(Jeffrey Lang, Struggling to Surrender, Maryland: Amana
Publications, 1994, p.92) and (Edward Said, Orientalism, NY:
Pantheon Books, 1978)
اور پھر خاص طور پر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے بارہ میں ایسا رویہ اختیار کرنا کہاں کی
دیانتداری اور علمی دُنیا میں کس مقام کا حامل ہوگا کہ جن کی سیرت اور سواخ مستند ترین تاریخی ثبوتوں کے ساتھ
نا قابل تردید دلائل سے بھری پڑی ہے کہ قرآن کریم آپ نے بلاتحریف و تبدل ہم تک پہنچایا ہے.کسی بھی تاریخی
طور پر مسلّمہ واقعہ کو اندازے لگا کر اگر رڈ کیا جانے لگا تو پھر کسی بھی چیز کی صداقت پر کھنے کی کوئی کسوٹی باقی نہ
رہے گی.اگر مستند تاریخی حقائق کو ان بے پر کے اندازوں سے آلودہ کیا جانے لگا تو تاریخ پر کون یقین کرے گا؟
لیکن افسوس صد افسوس کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ مکارم اخلاق کو نظر انداز کرتے ہوئے بار بار اس قسم
کے قیافے اور بلا ثبوت اندازے سادہ لوح اور نا واقف لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے پیش کیے جاتے ہیں اور مزید
حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ قرآن کریم میں رد و بدل کرنے کا کوئی ثبوت نہیں اور رد و بدل نہ کرنے کے بیشمار
ثبوت موجود ہیں.پھر جس شخص کا دن رات کا کام تعلیم قرآن ہو اس سے تو بھول چوک بھی محال نظر آتی ہے اور
دانستہ تبدیلی تو ممکن ہی نہیں رہتی کیوں کہ جب آیت ایک دفعہ لکھوا دی اور لوگوں نے حفظ کر لی اور اپنے پاس
تحریری صورت میں محفوظ کر لی تو پھر کیوں کر ممکن ہے کہ آنحضور کوئی تبدیلی کریں اور صحابہ سوال نہ اُٹھائیں اور
ہمعصر مخالفین بھی خاموشی اختیار کر لیں؟ ان تمام تر ثبوتوں کے باوجود بھی معاندین کارویہ نہیں بدلتا.اسی قسم کے
گندے اور خلاف واقعہ جملوں کے پر تبصرہ کرتے ہوئے حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب خلیفتہ اسیح الثانی
Page 138
الذكر المحفوظ
122
رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:
وو
مجھے تعجب آتا ہے کہ یہ لوگ تعلیم یافتہ کہلاتے ہوئے اور تہذیب کا دعویٰ کرتے ہوئے
کروڑوں انسانوں کے روحانی پیشواؤں پر قیاسی باتوں کی بنا پر کس طرح حملہ کر دیتے ہیں.حالانکہ خود ان لوگوں کے اخلاق اس قدر گرے ہوئے اور ذلیل ہوتے ہیں کہ انسانیت کو ان
سے شرم آتی ہے.ان کی یہ جرات محض اس وجہ سے ہے کہ اس وقت عیسائیوں کو حکومت حاصل
ے اور ان کو یہ شرم بھی نہیں آتی کہ جب مسلمان دنیا پر حاکم تھے اور مسیحیوں کا حال اس سے بھی پتلا
تھا کہ جو اس وقت مسلمانوں کا مسیحیوں کے مقابل پر ہے اس وقت بھی مسلمانوں نے یسوع ناصری
کے بارہ میں سخت الفاظ
کبھی استعمال نہیں کیے.مسلمانوں نے ہزار سال تک مسیحی ممالک پر حکومت
کر کے ان کے سردار کی جس عزت کا اظہار کیا کاش مسیحی لوگ دو تین سو سال کی حکومت پر ایسے مغرور
نہ ہو جاتے کہ اس نبیوں کے سردار پر اس طرح درندوں کی طرح حملے کرتے اور مسلمانوں کے اس
احسان
کا کچھ تو خیال کرتے کہ انہوں نے یسوع کے خلاف کبھی جارحانہ قدم نہیں اُٹھایا.“
( تفسیر کبیر جلد اول صفحه 253)
اس بحث کے دراصل دو پہلو ہیں.اول یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس درجہ بلند کردار اور اعلیٰ اخلاق
کے مالک انسان تھے کہ آپ کی ذات سے ادنیٰ سی بددیانتی کا تصور کرنا بھی محال ہے.دوسرا پہلو یہ ہے کہ
آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری کی بحث نہیں.نزول قرآن کے وقت خدا تعالیٰ کی تقدیر اور منشاء کے
مطابق حالات ہی ایسے تھے کہ اگر آپ چاہتے بھی تو قرآن کریم میں رد و بدل نہیں کر سکتے تھے.ذیل میں ہم
دونوں پہلوؤں پر باری باری بات کرتے ہیں.و,
جہاں تک ابن وراق کے اس قول کا تعلق ہے جو وہ شیطانی آیات کے قصہ کا ذکر کرنے کے بعد کہتا ہے کہ
یہ قصہ ظاہر کرتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کچھ آیات خرد برد کی ہیں اور پھر اپنے اس لچر اعتراض کو
قومی کرنے کے لیے عبد اللہ بن سعد ابی سرح کا قصہ تاریخی طور پر مسخ کر کے پیش کرتا ہے، تو اس ضمن میں عرض
ہے کہ ان دونوں واقعات کی حقیقت تو قاری پر روشن ہو گئی ہے پس ان کو بنیاد بنا کر جو نتیجہ نکالا جارہا ہے کہ
نعوذ باللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم دیانتداری کے اعلیٰ معیار پر قائم نہیں تھے ، وہ بھی ڈھے جاتا ہے.بلکہ
نتیجہ اس کے برعکس نکلتا ہے کہ دراصل رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا مقابلہ انتہائی درجہ کی جھوٹی اور فریب
دینے والی قوم سے تھا اور اس واقعہ سے آپ کے مخالفین کی بد دیانتی ظاہر ہوتی ہے.وہ تو کھلم کھلا تسلیم کرتے تھے
کہ جہاں بھی انہیں موقع ملے گا وہ اسلام کو مٹانے کے لیے کوئی بھی جھوٹ گھڑ سکتے ہیں.چنانچہ ہر قل شاہ حبشہ
اور ابوسفیان کے مابین جو بات چیت ہوئی اس میں ابو سفیان اپنی اسی نیت کا اعتراف کرتا ہے کہ اگر موقع ملتا تو
Page 139
قرآن کریم میں تحریف کے الزامات کے جواب
123
ضرور جھوٹ بولتا ( بخاری کتاب بدء الوحی باب بدء الوحی ) مگر مزید یہ بیان کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ
رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی زندگی کے مطالعہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کسی بھی موقع پر آپ کے بارہ
میں یہ شک کیا ہی نہیں جاسکتا کہ آپ ادنی سی بھی بددیانتی کے مرتکب ہو سکتے ہیں.قرآن کریم کا معاملہ تو بہت
بڑا معاملہ ہے، آپ کی سیرت و سوانح کے مطالعہ سے یہ حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ کسی
چھوٹے سے چھوٹے معاملہ میں بھی آپ کی ذات کی طرف کوئی بھی ادنیٰ سے ادنی بددیانتی کبھی منسوب کی ہی
نہیں جاسکتی اور دوست تو دوست دشمن بھی اس حقیقت کے قائل ہیں.خدا تعالی بھی گواہی دیتا ہے کہ آپ نے
کوئی تبدیلی نہیں کی اور مومنین بھی یہی گواہی دیتے ہیں.بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عصر مخالفین بھی
یہی گواہی دیتے اور کھلم کھلا اعتراف کرتے ہیں کہ انہیں اپنی ذات سے زیادہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی
اور دیانتداری پر یقین ہے.ذیل میں ہم نعلی اور عقلی دلائل کی روشنی میں اس حقیقت کا مطالعہ کرتے ہیں.قرآن کریم سے ثبوت
قرآن کریم میں بار بار یہ گواہیاں ملتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے پوری دیانت داری کے ساتھ ،
بناتحریف و تبدل کے قرآن کریم ہم تک پہنچایا
ہے اور اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:
قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَا اثْتِ بِقُرْآن غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي
أَنْ أُبَدِلَهُ مِنْ تِلْقَايُّ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ
عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (يونس: 16)
ترجمہ: وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی توقع نہیں رکھتے کہتے ہیں اس کی بجائے کوئی اور قرآن
لے آ، یا اسے ہی تبدیل کر دے.تو کہہ دے کہ مجھے اختیار نہیں کہ میں اسے اپنی طرف سے بدل
دوں.میں تو اس کی ہی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے.اگر میں اپنے رب کی
نافرمانی کروں تو میں اتنینا ایک عظیم دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں.حضرت خلیفتہ اسیح الثانی رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں:.مطلب یہ ہے کہ میں قرآن مجید کے متعلق تمام باتیں وحی الہی سے کرتا ہوں اور اس میں
خود کوئی دخل نہیں دیتا.لہذا میں کوئی تبدیلی یا تغیر نہیں کر سکتا.اس آیت سے ان لوگوں کا بھی رڈ
ہو جاتا ہے جو کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ہر سورۃ سے پہلے لکھنا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کے حکم سے ہے نہ کہ وحی سے.یا ترتیب قرآن اور سورتوں کے نام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
Page 140
الذكر المحفوظ
124
نے خود رکھے ہیں.کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کی طرف سے فرماتا ہے کہ قرآن مجید سے متعلق میں ہر
بات کو وحی سے ہی طے کرتا ہوں اور یہ کہنا کہ بے شک رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم تو وحی الہی
سے ایسا کرتے تھے مگر صحابہ نے اپنی مرضی سے بعض تغیرات کر دیئے.بالکل ہی خلاف عقل
ہے.کیونکہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم کوحق نہیں تھا تو صحابہ کو کیسے یہ حق حاصل ہوسکتا تھا
اور وہ ، سوائے اس کے کہ نعوذ باللہ انہیں مرتد قرار دیا جائے کب ایسا کر سکتے تھے؟“
( تفسیر کبیر جلد 3 صفحہ 45 زیر تفسیر یونس : 16)
حضرت امام رازگی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:
سورۃ یونس کی اس آیت کے تحت کئی مفسرین نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ قرآن مجید کی
ترتیب خود خدا تعالیٰ نے قائم کی تھی اور اپنے رسول کو اس بات کا کوئی اختیار نہیں دیا تھا کہ اپنی
66
مرضی سے قرآن کریم کی ترتیب میں کوئی تصرف کرتے.“
(تفسير كبير لالررازى الجزء 17 صفحه 55 56 دار الكتب العلميه تهران الطبع الثاني)
تفسیر القرطبی میں سورۃ یونس آیت 16 کے تحت لکھا ہے.یہ آیت اس بارہ میں ہے کہ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا کہ
قرآن کو کسی اور ترتیب سے پیش کریں مگر آپ کو اس کا اختیار نہ تھا.اور یہ بات بھی مدنظر
رہے کہ جو کچھ بھی آپ فرماتے تھے جب کہ وہ وحی پر مبنی تھا تو وہ خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا
نہ کہ آپ کی طرف سے.(محمد بن عبدالله القرطبي : الجامع لاحكام القرآن جزو 8صفحه 319)
تفسیر القاسمی میں سورۃ یونس آیت 16 کے تحت لکھا ہے:
یعنی کفار نے آنحضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ اس قرآن کو کسی اور ترتیب
سے یا کسی اور شکل میں پیش کریں.اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ جواب سکھایا کہ قُلُ
مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِی یعنی یہ کام میرے ہاتھ میں نہیں.میں تو اللہ
تعالی کی کہی ہوئی بات بعینہ پہنچانے پر مامور ہوں.(محمد جمال الدين: محاسن التاويل تفسير القاسمی جلد 6صفحه 14)
ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ یہ گواہی ان الفاظ میں درج فرماتا ہے:
بالْحَقِّ أَنْزَلْنَهُ وَ بِالْحَقِّ نَزَلَ (بنی اسرائیل : 106)
یعنی حق کے ساتھ یہ کلام ہم نے نازل کیا اور حق ہی کے ساتھ ہی یہ نازل ہوا.
Page 141
قرآن کریم میں تحریف کے الزامات کے جواب
125
وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ ايَتٌ مِّنْ رَّبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْأَيتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا
نذِيرٌ مُّبِينٌ - (العنكبوت:51)
یعنی اور وہ کہتے ہیں کہ اس پر کوئی آیت کیوں نازل نہیں ہوتی.تو کہہ دے کہ آیات تو اللہ
کے پاس ہیں.میں تو صرف ایک واضح طور پر متنبہ کرنے والا ہوں.گو یا جب کسی معاملہ میں کفار کوئی آیت طلب کرتے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم فرماتے کہ یہ سب تو
خدا تعالیٰ کے اختیار میں ہے.میں اپنی طرف سے کوئی آیت کیسے پیش کر سکتا ہوں؟ اور اس بات کا ذکر کر کے
اللہ تعالیٰ نے یہ گواہی دے دی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے کبھی قرآن میں اپنی طرف سے کوئی آمیزش
نہیں کی.پھر خدا تعالیٰ قرآن کریم کو غیر اللہ کے دخل سے بکلی پاک ہونے کی ایک ایسی دلیل دیتا ہے جس کی
بنیاد پر ہر زمانہ میں قرآن کریم کی حفاظت کو پر کھا جاسکتا ہے.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:
لَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا (النساء: 83)
اگر یہ قرآن خدا کے سوا غیر اللہ کی طرف سے بھی ہوتا تو اس میں بہت اختلاف ہوتا.قرآن کریم کی تعلیمات پر نظر ڈالنے سے بخوبی علم ہو جاتا ہے کہ یہ بہر حال کلامِ الہی ہی ہے.قرآن میں
ایسی تعلیمات اور ایسے علوم کی طرف راہنمائی ہے کہ اس کو بہر حال خدا کا کلام تسلیم کرنا پڑتا ہے.اس بات کو
اختلاف مذاہب اور اختلاف عقیدہ کے باوجود گزشتہ چودہ سو سال میں ساری دُنیا میں اہل علم تسلیم کرتے رہے
ہیں کہ رسول کریم کے زمانہ میں جب کہ سائنسی علوم میں اتنی ترقی نہیں ہوئی تھی ، کس طرح قرآن کریم جدید
سائنس کے مطابق حقائق بیان کرتا ہے اور کئی سر بستہ رازوں سے پردہ اُٹھاتا ہے.اگر یہ کلام خدا تعالیٰ کی طرف
سے نہیں تو پھر آج قانون قدرت سے اس کا اختلاف نظر آجاتا جیسا کہ دوسرے مذہبی صحائف میں نظر آتا ہے.یہاں یہ نتیجہ بھی نکلتا ہے کہ اگر قرآن میں کوئی بات بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے اپنی طرف سے شامل
کی ہوتی تو اس آیت لوگـانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيْهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا (یعنی اگر یہ قرآن خدا
کے علاوہ کسی اور کسی طرف سے ہوتا تو اس میں ضرور کثیر اختلاف ملتا) کے تحت یہ قلعی کھل چکی ہوتی.کیسے ممکن
ہے کہ ایسے کلام میں جو انسانی دسترس سے بالا ہو، کوئی انسانی کلام مل جائے اور پھر اس طرح مل جائے کہ انسانی
کلام اور کلام الہی بالکل مشابہ ہو جائیں اور دونوں میں باہمی فرق ہی نہ کیا جا سکے؟ یوں تو قرآن کریم اپنے
الہی کلام ہونے کے دلائل بہت تفصیل سے بیان کرتا ہے.مگر براہ راست مضمون سے تعلق نہ ہونے کی وجہ سے ہم
اس تفصیل میں نہیں جاسکتے اور صرف آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق فاضلہ جو آپ کی صداقت کا ثبوت ہیں،
تک ہی محدود رہتے ہیں گو یہ احساس بھی اپنی جگہ موجود ہے کہ یہ مضمون بھی فی ذاتہ لامحدود ہے.
Page 142
الذكر المحفوظ
126
محمد هست بر بان محمد
قرآن کریم آنحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے اسوہ اور آپ کی راستبازی کو آپ کی صداقت کی ایک دلیل
کے طور پر پیش کر کے مخالفین کو ملزم کرتا ہے.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:
قُلْ لَّوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَكُمْ بِهِ رَفَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا
مِن قَبْلِهِ طَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (يونس: 17)
یعنی کہہ دے کہ اگر اللہ چاہتا تو میں تم پر اس کی تلاوت نہ کرتا اور نہ ہی تمہیں اس بارہ میں
کچھ بتا تا.میں تم میں اس سے پہلے ایک عمر گزار چکا ہوں.کیا تمہیں عقل نہیں ؟
ذیل میں ہم آنحضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے اخلاق فاضلہ کے حوالہ سے آپ کی سوانح کا مطالعہ کر کے اس
معاملہ میں روشنی حاصل کرتے ہیں کہ آیا اس بلند کردار کا انسان قرآن کریم میں تحریف کا مرتکب ہوسکتا تھا؟
آنحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی سوانح حیات ایک آپ کے دیانت دار ہونے ایسا نا قابل تردید ثبوت ہے
جو آپ کی ذات کے حوالہ سے پیدا کیے جانے والے تمام تر شکوک کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتا ہے.ایک شخص جو اپنے
روزمرہ کے معاملات میں اتنے شفاف کردار کا حامل ہے کہ ساری زندگی کسی ایک جھوٹ اور ادنی سی بھی بد دیانتی
کا مرتکب نہیں ہوا ، کیسے ممکن ہے کہ پہلی بددیانتی ہی اتنی بڑی کرے کہ خدا تعالیٰ کے معاملہ میں جھوٹ گھڑ کر بنی نوع
کو گمراہ کرنا شروع کر دے.آنحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم چالیس سال تک ایک ایسے شہر میں سکونت پذیر رہے
جو کئی لحاظ سے عرب کا مرکز تھا اور اس مرکزی شہر میں آپ نے ایک بھر پور معاشرتی زندگی گزاری.ایک ایسی
معاشرتی زندگی کہ سارا معاشرہ آپ کی زندگی کے شب و روز کا معائنہ کرنے کے بعد آپ کے اعلیٰ اخلاق اور
عادات اور اُجلے چال چلن کا گواہ بن چکا تھا.زندگی کا کوئی ایک پہلو بھی ایسانہ بچا تھا جودُنیا کی نظروں سے اوجھل
رہا اور لوگوں کے سامنے نہ آیا.پس اس معاشرہ سے جب ہم آپ کی سیرت کے بارہ میں معلومات اکٹھی کرتے
ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ گھر سے باہر اور گھر کے اندر ہر جگہ آپ کی عظمت کردار کی گواہیاں بکھری پڑی ہیں.سب
سے پہلے ہم آپ کی صداقت اور دیانت کے حوالہ سے آپ کی حیات مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں.آنحضرت ﷺ کی صداقت اور دیانت پر گواہیاں
آنحضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی صداقت کی اور آپ کے امانت دار ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل آپ کے
ابتدائی اسلام لانے والے صحابہ ہیں.آپ پر پہلے ایمان لانے والے نہ تو کوئی اجنبی تھے اور نہ ہی نا واقف.بلکہ
سب سے پہلے وہی لوگ ایمان لائے جو آپ کو قریب سے دیکھ اور پر کچھ چکے تھے اور آپ کی زندگی کے لمحہ لمحہ کے
Page 143
قرآن کریم میں تحریف کے الزامات کے جواب
127
گواہ تھے.کس طرح ممکن ہے کہ ایک شخص دھوکہ دہی کا مرتکب ہورہا ہو اور اس کے دھو کے میں سب سے پہلے وہ
لوگ آئیں جو ا سے سب سے زیادہ جانتے ہوں؟ یہ شہادت ایسی مضبوط ہے کہ کسی دشمن کو بھی اس کے تسلیم کرنے
کے سوا چارہ نہیں.چنانچہ جان ڈیون پورٹ آپ کے بارہ میں رقم طراز ہیں:
"It is strongly corroborative of Mohammed's sincerity
that the earliest converts to Islam were his bosom friends
and the people of his household, who, all intimately
acquainted with his private life, could not fail to have
detected those discrepancies which more or less
invariably exist between the pretensions of the
hypocritical deceiver and his actions at home."
(John Davenport: An Apology for Mohammed and the Koran,
London: 1869 P.17)
یعنی محمد (صلی اللہ علیہ والہ وسلم) کے صداقت کی بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ آپ پر ایمان
لانے والے ابتدائی لوگوں میں آپ کے قریبی دوست، گھریلو تعلقات والے افراد تھے جن کا
آپ کی ذاتی زندگی سے قریبی واسطہ تھا، جنہیں کبھی کوئی ایسی معمولی سی بات بھی نہیں ملی جو ایک
دھوکہ دینے والے کی معاشرتی زندگی اور ذاتی زندگی میں فرق کرتی ہے.اس حوالہ سے جب ہم آپ کی سوانح پر نظر ڈالتے ہیں تو حیرت انگیز اور ناقابل تردید دلائل کا انبار نظر آتا
ہے.مثلاً آپ نے ایک شوہر کے طور پر زندگی گزاری بیوی انسان کی سب سے قریبی ساتھی ہوتی ہے،اس
سے خاوند کی کمزوریاں بھی چھپی نہیں رہ سکتیں اور خوبیاں بھی دوسروں کی نسبت اس کی نظر میں پہلے آجاتی ہیں.حضرت خدیجہ کی ایک گواہی تو آپ کی زندگی کے تمام پہلوؤں کے بارہ میں ہے.یعنی ایک تو وہ گواہی ہے جو
آپ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی تجارت میں دیانت داری اور صداقت کا سن کر عملی انداز میں یوں دی
کہ آپ سے شادی کر کے اپنا سب کچھ آپ کو سونپ دیا.مگر کیا یہ ملی گواہی کسی غلط فہمی کا نتیجہ تھی؟ کیا آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے اسوہ سے خلاف واقعہ
متاثر ہوئی تھیں؟ نہیں بلکہ یہ گواہی آنحضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے ساتھ رہنے اور آپ کی زندگی کا قریب سے
مطالعہ کرنے کے بعد اور بھی نکھر کر سامنے آئی.حضرت خدیجہ شادی کے قریباً 15 سال آپ کے ساتھ گزار نے
کے بعد بھی کیا گواہی دے رہی ہیں، ملاحظہ کریں.بخاری کی ایک لمبی روایت ہے جس میں ذکر ہے کہ جب
حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم پہلی وحی کے بعد انتہائی درجہ احساس ذمہ داری کی وجہ سے گھبرائے ہوئے
گھر واپس آئے اور حضرت خدیجہ سے اپنی پریشانی کا ذکر کیا تو آپ نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا:
Page 144
الذكر المحفوظ
128
كلا والله ما يخذيك الله ابدا انك لتصل الرحم وتصدق الحديث
بخاری کتاب بدء الوحي باب بدء الوحى)
یعنی ہرگز نہیں ! اللہ کی قسم! اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز رسوا نہیں کرے گا.آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں
اور راست گوئی سے کام لیتے ہیں.اور پھر اس گواہی کو اس وفا شعار بی بی نے شعب ابی طالب کے مصائب سے اٹے ہوئے اور مشکلات سے
پُر دور میں رات دن ساتھ رہ کر اور بھی زیادہ مضبوط کیا.بیوی کی گواہی تو ہم نے دیکھی.یہ کوئی ایسی گواہی نہیں کہ
عام نظروں سے دیکھی جائے.دن رات کا ساتھ اور 15 سال میں ہزاروں چھوٹے بڑے معاملات میں آپ
کے اسوہ کا بنظر غور مطالعہ کرنے کے بعد یہ گواہی دی جارہی ہے.اب بیٹی کی گواہی بھی سینے.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب بیٹی حضرت فاطمہ، آپ کی آخری بیماری میں
ایک دفعہ آپ کے پاس بیٹھی تھیں.آپ نے ان کے کان میں کچھ کہا تو وہ رونے لگ گئیں.آپ نے پھر ان کے
کان میں کچھ کہا تو وہ ہنسنے لگیں.آپ کی وفات کے بعد لوگوں نے ایک مرتبہ رونے اور دوسری مرتبہ ہنسنے کا سبب
چھا تو کہا کہ پہلی بار آپ نے یہ خبر دی کہ اسی مرض میں میری وفات ہو جائے گی.یہ سُن کرمیں رونے لگی.پھر
آپ نے بتایا کہ اہل بیت میں سے میں وہ پہلی فرد ہوں گی جو آپ کے بعد فوت ہو کر آپ سے ملوں گی.یہ سن کر
میں بہنے لگی.(بخاری کتاب المغازی باب مرض النبی و وفاته ) ذراغور کیجیے کبھی کوئی اپنی موت کی خبرن
کر بھی ہنسا ہے؟ یہ نسی ایک بیٹی کی اپنے باپ کی صداقت کی کتنی بڑی گواہی ہے کہ ساری زندگی اپنے باپ (ﷺ) کو
قریب سے دیکھنے کے بعد اسے اپنے باپ (ﷺ) کی سچائی پر پورا پورا یقین ہے کہ جس طرح زندگی میں
کبھی غلط
بیانی نہیں کی اسی طرح وہ تمام بشارتیں جو اس نے اپنی بیٹی کو بعد الموت اپنی اور بیٹی کی قربت اور جنت کی سیادت
کی دی ہیں وہ برحق اور ضرور پوری ہونے والی ہیں.پس اگر یہ یقین ہو تو پھر کون موت کی خبر ہنس کر نہ سنے گا ؟
بیوی کی گواہی سنی ، بیٹی کی سنی.اب ذرا ایک قریبی دوست کی گواہی بھی سُن لیجیے.حضرت ابوبکر جب
آنحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے خدا کی طرف سے رسول ہونے کا دعویٰ کیا تو حضرت ابوبکر شہر سے باہر تھے.جب واپسی کے راستہ میں لوگوں سے آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت کے بارہ میں سُنا تو فی الفور آپ کی
خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ کیا جو انہوں نے سُنا ہے وہ سچ ہے؟ آنحضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے
اپنے دعوی کی صداقت کے ثبوت میں کچھ کہنا چاہا تو عرض کی کہ صرف یہ بتادیجئے کہ آیا جومیں نے سُنا ہے وہ سچ
ہے؟ آپ نے پھر کچھ بتانے کے لیے لب کھولے تو پھر عرض کی صرف یہ بتادیجیے کہ آپ نے ایسا دعویٰ کیا ہے؟
جب آپ نے اثبات میں جواب دیا تو حضرت ابو بکر فوراً ایمان لے آئے اور کوئی دلیل طلب نہ کی اور
Page 145
قرآن کریم میں تحریف کے الزامات کے جواب
129
طلب کرنے کی ضرورت بھی اس لیے محسوس نہ کی کہ آپ کی زندگی کے شب و روز ان کے سامنے تھے جو
حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یہ ماننے پر مجبور کر رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے سوائے سچائی کے اور کچھ
نکل ہی نہیں سکتا.(بخاری کتاب المناقب باب مناقب ابوبکر)
دور
آپ نے ایک بہت ہی بھر پور سماجی زندگی گزاری.تفصیل کے بیان
کا تو موقع نہیں لیکن ایک طائرانہ نگاہ
ڈالیے.خانہ کعبہ کی تعمیر میں رضا کاروں کے ساتھ مل کر کام
کیا....جنگ کے دوران افواج کی مددکی...اصلاح معاشرہ کی خاطر بنائی گئی تنظیموں میں بھی شامل ہوتے رہے جیسے حلف الفضول.....سماجی تقریبات میں
بھی شریک ہوتے رہے.لین دین کے معاملات کی طرف نظر کیجیے.پھر بڑے بڑے کامیاب تجارتی
ورے کیے...اتنی بھر پور اور کھلی کتاب کی مانند سماجی اور معاشرتی زندگی گزاری کہ اس کی مثالوں سے تاریخ
بھری پڑی ہے.ان سب پہلوؤں پر قریب سے نظر کرنے کے بعد پھر اس قوم کا آپ کو صادق اور امین کا
خطاب دینا ایک ایسی گواہی ہے کہ اس شان کی گواہی اور کسی شخصیت کے حق میں کبھی نہیں دی گئی.یہ ایک ایسی
گواہی ہے کہ ہر قسم کے تعصب کو چیرتی ہوئی آج بھی مخالفین کے دلوں کی گہرائیوں سے نکل آتی ہے.چنانچہ
و بیلیم میور جیسا متعصب انسان بھی یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ:
"Our authorities all agree in ascribing to the youth of
Mohammad a modesty of deportment and purity of
manners rare among the People of Mecca...Endowed
with a refined mind and delicate taste, reserved and
meditative, he lived much within himself, and the
ponderings of his heart no doubt supplied occupation
for leisure hours spent by others of a lower stamp in
rude sports and profligacy.The fair character and
honorable bearing of the unobtrusive youth won the
approbation of his fellow-citizens; and he received the
title, by common consent, of Al-Ameen, the
Trustworthy."
(William Muir:Life of Mohammad,London1903.Intorduction pg17)
یعنی ہماری تمام تر تحقیقات اس معاملہ میں متفق ہیں کہ محمد (ﷺ) کی جوانی توازن اور
پاکیزگی کا شاہکار تھی جو اس دور کے عربوں میں مفقود تھا.ایک اُجلا ذہن اور نفیس طبیعت،
مفکرانہ انداز، وہ اپنے آپ میں ہی مگن رہتے تھے.اپنے دل میں
کسی گہری سوچ میں غرق.اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ نے بہت سے قیمتی اوقات مراقبہ میں گزارے جبکہ دوسرے لوگ
وہ وقت کسی ادنی درجہ کی مصروفیت یا کھیل تماشہ میں گزار دیتے تھے.شفاف کردار اور جوانی کے
دنوں میں با کردار اطوار نے باقی بستی والوں کے دلوں کو جیت لیا تھا اور عوام میں آپ کو خطاب
Page 146
الذكر المحفوظ
ملا تھا الامین
130
سب سے بڑھ کر قابل اعتماد !
یہ ہیں میور صاحب.تعصب نے جوش مارا تو کہ دیا کہ ” ہو سکتا ہے کوئی ردو بدل کر دیا ہو.“ جب حقائق کا
مطالعہ کیا تو یہ گواہی دے دی.یہ ان متعصب مستشرقین کی فطرت کا حقائق سے تضاد کا ادنی سانمونہ ہے.معاشرہ میں ایسی نکھری اور اجلی شخصیت کے طور پر ایسا مشہور ہونا کہ ساری قوم کا آپ کو صادق اور امین کا
خطاب دے دینا، یہ حقیقت اور بھی واضح ہو جاتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس معاشرہ میں نیکی اور عمدہ چال چلن
بالکل معدوم ہو چکا تھا اور ان اقدار کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہی تھی.عزتوں کے پیمانے بدل چکے تھے.چنانچہ
اس دور کی تاریخ اور ادب جو وہ معاشرہ پیش کرتا ہے اس کے مطابق ظلم زیادتی ،فستق بدکاری، ناجائز حرکات اور
دیوشیت عظمت کے پیمانے ٹھہر چکے تھے اور اس دور میں حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا بے داغ
اسوہ اور بے نظیر اخلاق آج بھی تسلیم کیے جاتے ہیں.کسی صاف معاشرہ میں اچھا بن کر رہنا مشکل نہیں.لیکن ایک
گندگی سے لتھڑے معاشرہ میں بے داغ کردار یقیناً عام حالات کی نسبت بہت زیادہ غیر معمولی بات ہے.عرب کی اخلاقی اور سماجی حالت کو ذہن میں رکھتے ہوئے غور کریں کہ اس دور میں ایسے اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ
اس شان سے کرنا کہ پورا سماج آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتے ہی عظمت اور شوکت کے اپنے خود ساختہ
پیمانوں
کو خود ہی تو ڑ دیتا تھا اور آپ کے صادق اور امین ہونے کی گواہی دینے لگتا.کس درجہ عظیم الشان گواہی ہے!
کس قدر مجبور تھی وہ قوم کہ جن کے ارباب بسط و کشاد، جب بھی حقیقی عزت اور مرتبہ کی بات آتی تو سر اسی نوجوان
کے آگے جھکاتے.پھر جب آنحضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی بعثت ہوئی تو پہلے قوم کو گواہ بنایا کہ تم بتاؤ کہ اب تک
کی زندگی پر تو تمہیں کوئی اعتراض نہیں؟ اور پھر قوم کا گواہ بن جانا اور اس وقت یہ اعتراف کرنا کہ تمہاری گزشتہ
زندگی اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی ایسی بات تمہارے منہ سے نہیں نکلی اور نہ ہی نکل سکتی ہے جو جھوٹی، نا قابل
اعتبار اور سچائی کے معیار سے گری ہوئی ہو.جسے ہم رو کر سکیں اور گواہی بھی اس شان
کی کہ کوئی ایک بھی تو نہ تھا جو
پیچھے ہٹا ہو یا قوم کی گواہی میں اپنی گواہی شامل کرنے سے ذرہ بھی ہچکچایا ہو.فرمایا اگر میں کہوں کہ اس پہاڑی کے
پیچھے ایک لشکر تمہاری تباہی کی غرض سے جمع ہے تو میری بات مان لو گے؟ سب نے بیک زبان کہا کہ ہاں !!!
کیوں کہ آپ صادق اور امین ہیں اور آپ کی ذات سے ہمیں کبھی جھوٹ
کا تجربہ نہیں ہوا.یہ اقرار کوئی عام اقرار
نہ تھا، قومی اقرار تھا.ذرا نظر غور دیکھیے کہ اس قوم کو آنحضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی صداقت پر کس قدر کامل یقین
تھا کہ اہل مکہ کے چروا ہے روزانہ اپنے مویشیوں کے ساتھ دور دور تک نکلتے تھے.صبح سے شام تک وہ لوگ صحرا نوردی
کرتے.جب بھی حملہ ہوتا تو سب سے پہلے چرواہے ہی شکار بنتے.پس اگر در حقیقت کوئی لشکر ہوتا تو لازماً ان کو
خبر ہوتی.کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ وہ اپنے مویشیوں کے ساتھ خیر وعافیت سے لوٹے تھے اور اب اس دعوت میں
Page 147
قرآن کریم میں تحریف کے الزامات کے جواب
131
شریک تھے.انہوں نے اپنی آنکھوں کو تو جھٹلا دیا جو ابھی ابھی سب کچھ دیکھ آئی تھیں اور ”صادق“ کی خبر کو تسلیم
کرنے کا اعلان کیا اور اپنی آنکھوں سے زیادہ ”آمین“ پر اعتماد کیا.کیا کوئی اور مثال ہے کہ پوری قوم کے لوگ اپنی
اپنی ذات پر یقین کرنے سے زیادہ کسی ایک انسان کی صداقت پر یقین رکھتے ہوں؟ اس اعلان کو وہ لوگ سُن
رہے تھے جو ابھی صحرا سے لوٹے تھے اور اب اس کی بات سُن رہے تھے جس کی شہادت پر اپنی آنکھوں کی شہادت
سے زیادہ اعتبار تھا.تاریخ میں کسی کی صداقت پر اتنی مضبوط گواہی کوئی اور ہے تو سامنے لاؤ.تاریخ کے صفحات
میں صرف ایک انسان ہی اس شان کا ہے اور بس.پس جب فرمایا اگر میں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشک
تمہاری تباہی کی غرض سے جمع ہے تو کیا تم مان لو گے؟ سب نے بیک زبان کہا ہاں کیوں کہ آپ صادق اور امین
ہیں.کیا ہی عظیم گواہی دی اس قوم نے اس موقع پر کہ ما جربـنـا عليك الاصدقا“ (بخارى كتاب
سیر القرآن باب انذر عشیرتک الاقربین [الشعراء: 132]) کہ آپ کی ذات سے ہمیں ہمیشہ سچ ہی کا
تجربہ ہوا ہے.وہ عرب کے وہ بدو رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی چالیس سالہ زندگی کی تاریخ اور اس قانون
شہادت کو کس طرح جھٹلا سکتے تھے جن کی گواہ تین نسلیں وہاں موجود تھیں.وہ بظاہر ایک جاہل اور وحشی قوم تھی مگر
دلیل اتنی واضح ، آسان فہم اور قوی پیش کی جارہی تھی کہ بظاہر ایک بعید از قیاس بات بھی ماننے پر مجبور تھے.حضرت محمدصلی اللہ علیہ وسلم اپنی گزشتہ زندگی کا حوالہ دے کر قوم سے بات کر رہے تھے جو حوالہ ماننے پر اس معاشرہ کا
ہر شخص مجبور تھا.اللہ اللہ کس شان کی گواہی ہے.اگر میں کہوں کہ ایک لشکر جرار اس پہاڑ کے پیچھے سے تم پر حملہ
کرنے کو تیار کھڑا ہے.یعنی تم کہ جو ابھی ابھی اس دشت سے لوٹے ہو.سب کچھ خود دیکھ آئے ہو.اب بتاؤ اپنی
آنکھوں کو جھٹلاتے ہو یا مجھے جھوٹا کہتے ہو؟ بیسیوں سرکس طرح جھک گئے جب وہ پر شوکت آواز بلند ہوئی.سُننے
والے آج بھی ان صداؤں کو سُن سکتے ہیں جو ان جھکی گردنوں کی تھیں کہ بخدا! اپنا آنکھوں دیکھا تو جھٹلا سکتے ہیں مگر
اس صدوق کی خبر کو نہیں جھٹلا سکتے.ہزار ہا اخلاقی گراوٹوں کے باوجود اہل مکہ ابھی ابن وراق کے پاسنگ کو بھی نہیں
پہنچے تھے کہ چڑھتے سورج کا انکار کر دیں.یہی تو وہ قانون شہادت ہے جس پر آج تک دُنیا قائم ہے.یہاں
ابن وراق کے اس کتاب کے لکھنے کے بعد چھپ جانے کی وجہ پھر کھل جاتی ہے کہ ایسی حرکت کر بیٹھا ہے کہ جانتا
ہے کہ اس کے بعد دُنیا کو مُنہ دکھانے کے قابل نہیں رہا.غرض رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر لحاظ سے اس معاشرہ کو یہ موقع دیا کہ وہ آزمالیں ، دیکھ لیں اور گواہ
بن جائیں.چالیس سال کوئی ایسا معمولی عرصہ نہیں کہ اس کی تاریخ عالم میں کوئی مثال مل سکے کہ ایک شخص نے
اس عرصہ میں اپنی قوم میں ایک بھر پور سماجی زندگی گزاری ہو اور پھر قوم اس کی صداقت پر ایسی متفق ہوگئی ہو کہ اپنی
آنکھوں کو جھٹلانا تو آسان لگے مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات
کو جھٹلانا بس میں نہ رہے.ایک دشمن زبان
Page 148
الذكر المحفوظ
132
اس موقعہ پر یہ کہ سکتی ہے کہ اس وقت تک قوم کو اس بات
کا علم نہیں تھا کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے.اس لیے سب
نے آپ کی صداقت کی گواہی دے دی.مگر ہم کہتے ہیں کہ اس کی قوم تو 13 سال تک اس کے دعوی کے بعد بھی
اسے سچاہی بجھتی رہی اور یہی گواہی دیتی رہی.ابو جہل کا وہ قول کیوں بھلا دیتے ہو انــا لا نـــذبـک ولکن
نكذب بما جئت به یعنی اے محمدہم مجھے جھوٹا نہیں کہتے.ہم تو اس تعلیم کا انکار کرتے ہیں جوتو لایا ہے.(ترمذى ابواب التفسير باب ومن سورة الانعام ) ہر قل کے دربار میں ابوسفیان کی گواہی بھی ایک نا قابل
تردید ثبوت ہے کہ رسول کریم ﷺ کے بارہ میں اپنوں اور بیگانوں میں متفق علیہ یقین تھا کہ آپ کامل طور پر
صادق انسان ہیں.چنانچہ جب ابوسفیان سے ہر قل نے پو چھا کہ کیا محمد ( ﷺ) نے کبھی جھوٹ بولا ہے تو اس
نے واضح طور پر کہا کہ ایسا کبھی نہیں ہوا.چنانچہ بخاری میں ہے:
هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل ان يقول ما قال قلت لا
(بخاری کتاب بدء الوحي باب بدء الوحى)
( ابوسفیان کہتا ہے کہ قیصر نے پوچھا کہ ) کیا تم اُس پر اُس کے اس دعوی سے قبل جھوٹا
ہونے کا الزام لگاتے تھے؟ تو میں نے جواب دیا؟ نہیں.ہر قل ایک جہاندیدہ اور عقل مند آدمی تھا وہ سمجھتا تھا کہ دعوی کے بعد تو اہل مکہ کچھ بھی کہتے ہوں گے کیونکہ دعویٰ
کے بعد تو دشمنی پیدا ہوگئی ہے اور تو مخالف جھوٹ کا الزام لگا سکتے ہیں لیکن اگر دعوی سے
قبل آپ کو سچا سمجھا جاتا تھا تو پھر
ناممکن ہے کہ روز مرہ زندگی کے معاملات میں سچائی کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دینے والا شخص خدا تعالیٰ کے معاملہ
میں راستی اور راستبازی کو چھوڑ دے.دیکھنے والی بات ہے کہ کیا اس دعوی سے قبل وہ محمد (ﷺ) کی طرف کوئی
جھوٹ منسوب کرتے تھے کہ نہیں.چنانچہ جب ابوسفیان نے باوجود دشمن ہونے کے آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی
صداقت کی گواہی دی تو ہر قل نے کیا خوب کہا:
الله
فَقَدْ أَعْرِفُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَذَرَ الْكَذِبَ عَلَى النَّاسِ وَ يَكْذِب عَلَى اللَّهِ
(بخاری کتاب بدء الوحي باب بدء الوحى)
یعنی میں اس بات کو اچھی طرح سمجھتا ہوں کہ جو شخص بنی نوع کے معاملات میں جھوٹ نہیں
بولتا ناممکن ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے معاملہ میں جھوٹ بولے.پس رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی ساری زندگی اس بات کی گواہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ اس پیغام کی
پوری دیانت داری سے حفاظت کی جسے آپ خدا کا پیغام کہتے تھے.بالکل اسی طرح جس طرح آپ اہل مکہ کی
امانتوں کی حفاظت کرتے تھے.کیا دشمن آنکھ کوئی ایک مثال دیکھ سکتی ہے ، کوئی ایک مثال کہ جب آپ غلط
بیانی یا دھوکہ دہی سے کام لیا ہو؟ وہ وقت تو یاد کریں جب کہ اہل مکہ کی چوٹی کی قیادت اس مسئلہ کو سلجھانے کے لیے
Page 149
قرآن کریم میں تحریف کے الزامات کے جواب
133
ایک جگہ موجود تھی.آج سیاست اور حکومت کے بل بوتے پر وہ لوگ مذہب کا فیصلہ کرنے چلے تھے اور تکبر ظلم اور
تعدی میں حد سے گزرتے ہوئے خدا تعالیٰ کا کام اپنے ہاتھ میں لے چکے تھے.وہ لوگ جائز اور ناجائز اور بیچ اور
جھوٹ میں تمیز کرنے کے لیے اکٹھے نہیں ہوئے تھے.ان کے اکٹھا ہونے کا مقصد ایک ہی تھا کہ اس مشن کو کسی
طرح بند کرنے کی کوئی ترکیب نکالی جائے اور اس کام کے لیے وہ ہر حربہ استعمال کرنے کے لیے تیار تھے.وہ
آج کی میٹنگ سے پہلے کتنے ہی حربے آزما چکے تھے اور نا کام ہو چکے تھے.پس آج کوئی بھی تدبیر ، ہاں جائز یا
ناجائز کوئی بھی تدبیر ہو تو لاؤ.کوئی ممکن العمل بات پیش کرو.ابھی ابوسفیان کی روایت کا ذکر گزرا ہے.اسی
روایت میں یہ ذکر ہے کہ ابو سفیان کہتا تھا کہ میں جھوٹ بولنا چاہتا تھا مگر مجھے کوئی موقع نہیں مل رہا تھا.گویا جانتا
ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم سچے ہیں اور اس کی گواہی بھی دے رہا ہے اور پھر بھی کوشش یہ جاری ہے کہ
کسی بھی طرح ، جھوٹ سے ہی سہی ، بس اس آواز کو دبا لیا جائے.آج ایک ابوسفیان اس بددیانتی کی کوشش نہیں
کر رہا بلکہ تمام قیادت متفقہ طور پر کوشش کر رہی ہے.آج کسی ہرقل کا خوف نہیں تھا.پھر یہ بھی ذہن میں رہے کہ
وہ ایسی قوم تھی جس کے فسق و فجور کی دُنیا آج بھی شاہد ہے.اسلام کے مستقبل کا فیصلہ کرنے کے لیے اس وحشی
قوم کی قیادت آج جمع تھی جن کے پاس کوئی ضابطہ اخلاق نہ تھا.مذہب وعقیدہ کے اختیار کی آزادی تو انسان کا
بنیادی حق ہے اور وہ ظالم حکومت اور طاقت کے زور پر یہ حق بھی چھین رہے تھے.سچ جھوٹ کا سوال نہیں تھا بس
کسی بھی ایسی تدبیر کی تلاش تھی جو کارگر ہو، خواہ جائز ہو یا نا جائز.وہ حیران تھے کہ دنیا کو مد (ﷺ) کے بارہ میں
کیا کہیں.مختلف تدابیر زیر غور تھیں.جب یہ بات چلی کہ دنیا کو یہ کیوں نہ کہہ دیا جائے کہ جھوٹ گھڑا جارہا ہے.تو اُن میں سے ایک سردار نضر بن الحارث اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ یہ بات ناممکن ہے کہ کوئی مان جائے.محمد (ﷺ) کے اعلیٰ اخلاق اور اس کی صداقت اور امانت ہی تو ایک ایسا عنوان ہے جس پر قوم متفق ہے.یہی تو
سب سے بڑی روک ہے.پس یہ کہنا کہ محمد ( نعوذ باللہ ) جھوٹا ہے گویا یہ کہنا تھا کہ اہل مکہ سب کے سب جھوٹے
ہیں جو مد (ﷺ) کو سچا کہتے ہیں.کون ہے جو ہم چند لوگوں کی بات مان کر ساری قوم کو جھوٹا کہے گا ؟ گویا رسول
کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانا ایک قوم کی متفقہ شہادت کو جھٹلا نا تھا.ہاں محمد مگا صادق اور امین ہونا ہی تو وہ حوالہ تھا
جو ان کی شیطانی چالوں کے آگے روک بنا ہوا تھا.چنانچہ فوراً ہی اس تدبیر کو اتفاق رائے سے رڈ کر دیا گیا.اس
گواہی کی عظمت کا صحیح اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب ہمارے علم میں یہ بات آتی ہے کہ نضر بن الحارث ان نو
افراد میں سے ایک تھا جنہوں نے آنحضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے قتل کی سازش کی تھی.اس گواہی کا یہ مطلب ہے
کہ گویا نضر بن الحارث کے لیے آنحضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کو جھوٹا قرار دینے کی نسبت آپ کو قتل کرنا آسان
تھا.آپ کا سب سے بڑا دشمن، ابو جہل جس نے اپنی زندگی اس مشن کی تباہی کے لیے وقف کر دی تھی، جب بھی
الله
Page 150
الذكر المحفوظ
134
سچ اور جھوٹ کا ذکر آتا تو بے اختیار ہو جاتا.لاچاری سے کہ اٹھتا کہ میں یہ کہ ہی نہیں سکتا کہ محمد(ﷺ ) جھوٹ
بول رہا ہے.ہاں زیادہ سے زیادہ یہ کہ سکتا ہوں اس کی تعلیم غلط ہے ( ترمذی ابواب النفسیر ).کوئی سردار ہر لحاظ سے
غور کرتا تو بے اختیار ہوکر کہہ اٹھتا کہ یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ محمد ( نعوذ باللہ ) غلطی خوردہ ہے مگر یہ نہیں کہ جھوٹ بول
رہا ہے.پھر امیہ بن خلف کو بھی نہ بھولو.بے شک وہ بھی آنحضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا جانی دشمن تھا مگر آپ کی
صداقت کی گواہی تو اس نے بھی دی تھی.وہ کہتا تھا " والله ما يكذب محمد اذا حدث “(بخاری کتاب
علامات النبوة) كه خدا کی قسم ! محمد ﷺ ) جب بات کرتا ہے تو جھوٹ نہیں بولتا! الغرض یہ وہ گواہیاں ہیں جو حضرت
رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے بارہ میں اُس دور میں اپنوں بیگانوں اور دوستوں اور دشمنوں نے دیں.حضرت فاطمہ الزہرا کی گواہی آپ نے سنی کہ کس طرح اپنے آقا کی صداقت پر یقین کامل تھا کہ موت کی خبر پر بھی
مسکرا دیتی ہیں.مگر بعینہ یہی گواہی ایک مخالف نے بھی تو دی.جب وہ جنگ اُحد کے خاتمہ کے بعد رسول خدا(ﷺ)
پر حملہ آور ہوا جب کہ آپ کو ہ اُحد پر پناہ گزین تھے.ایسے میں آپ نے کمال شجاعت اور مردانگی کا مظاہرہ کرتے
ہوئے صحابہ سے فرمایا کہ اسے حملہ آور ہونے دو اور نہ روکو اور خود آگے بڑھ کر اُس کے حملہ کے جواب میں اُس پر نیزہ
سے وار کیا.نیزہ اسے لگا اور وہ شخص دیوانہ وار چلا تا اور دہائی دیتا ہوا واپس بھاگ گیا.اس کی قوم نے اُسے کہا کہ اتنا واویلا
کرنے کی کیا ضرورت ہے.زخم کاری تو نہیں.اس پر وہ کہنے لگا کہ میں ضرور اس زخم سے مر جاؤں گا کیونکہ مجھے ایک دفعہ
محمد (ﷺ) نے کہا تھا کہ تیری موت میرے ہاتھ سے ہوگی.پس یہ تھا اُن لوگوں کا آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت
پر یقین اور یہ یقین غلط نہیں تھا.اُس شخص کی موت اُسی زخم سے ہوئی.(بخاری کتاب المغازی ابواب غزوہ اُحد)
پس اے دشمن نادان و بے راہ !!! ہمعصر نامی مخالفوں اور جانی دشمنوں نے بالا تفاق میرے آقا کو سچا اور
راستباز کہا ہے.اب تو اپنی حسرتوں کی آگ میں جل بھی مرے تو بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا.اور بالفاظ مسیح الزماں:
اے ایسی طبیعت کے آدمی!! تو بھی اس قادر مطلق سے خوف کر جس سے آخر کار تیرا معاملہ
ہے اور دل میں خوب سوچ لے کہ جو شخص حق کو پا کر پھر بھی طریقہ ناحق کو نہیں چھوڑتا اور مخالف پر
ضد کرتا ہے اور خدا کے پاک نبیوں کے نفوس قدسیہ کو اپنے نفس امارہ پر قیاس کر کے دنیا کے
لالچوں سے آلودہ سمجھتا ہے حالانکہ کلام الہی کے مقابلہ پر آپ ہی جھوٹا اور ذلیل اور رسوا ہورہا
ہے ایسے شخص کی شقاوت
اور بدبختی پر خود اس کی روح گواہ ہو جاتی ہے.براہین احمدیہ چہار حصص روحانی خزائن جلد اول صفحہ 353,354 ایڈیشن اول صفحہ 304 )
میرے آقا کی صداقت کی یہ گواہیاں تو آج بھی دی جارہی ہیں.ایک مستشرق ، واشنگٹن آئر ونگ ، آپ کی
سوانح کے مطالعہ کے بعد کہتا ہے:
"In his private dealings he was just.He treated friend
Page 151
135
قرآن کریم میں تحریف کے الزامات کے جواب
and strangers, the rich and the poor, the powerful and
the weak, with equity, and was loved by the common
people for the affability with which he received them,
and listened to their complaints."
(Washington Irving: Mahomet and his Successors, London
1909, pp.192)
یعنی اپنے روز مرہ کے معاملات میں آپ (ﷺ ) عدل وانصاف پر کار بند تھے.آپ نے واقف
اور ناواقف، امیر وغریب، طاقتور اور کمزور، سب کے ساتھ ہمیشہ برابری کا سلوک روارکھا، اور عوام میں اس
وجہ سے بہت محبوب ہو گئے کیونکہ آپ سب سے محبت سے پیش آتے اور ان کی حاجت روائی کرتے.ہم جھٹلانے والے سے پوچھتے ہیں کہ اس درجہ اعلیٰ اخلاق کا حامل انسان کہ جس کی سچائی پر اس قدر اندرونی اور
بیرونی دلائل اکٹھے ہو گئے ہوں کہ اب تک کسی کی سچائی پر اتنے دلائل مہیا نہ ہو سکے ہوں، جس کی سچائی کی گواہی اپنوں
نے دی اور بیگانے بھی اسے سچاہی کہتے رہے، دوست بھی اسے سچاہی کہیں اور دشمنوں کے پاس بھی اسے سچا تسلیم کرنے
کے سوا کوئی چارہ نہ ہو.ایک قوم نے بحیثیت قوم اس کے سچا ہونے پر گویا اجماع کر لیا، اُس پر ایکا ایک ایسی کیا مصیبت
ٹوٹی کہ اچانک اپنی ساری نیک نامی کو چھوڑ چھاڑ کر جھوٹ سے ایسا لپٹا کہ پھر موت تک اس سے الگ نہ ہوا.کیا یہ ممکن
ہے؟ پھر ساری زندگی کبھی عام انسانوں پر تو جھوٹ نہیں باندھا مگر اب جھوٹ باندھا بھی تو خدا پر.کیا یہ ممکن ہے؟
حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں:
” بے انصافی ان کی اس سے ظاہر ہے کہ اگر مثلاً کوئی عورت کہ جس کی پاک دامنی بھی کچھ
ایسی ویسی ہی ثابت ہو.کسی ناکردنی فعل سے متہم کی جائے تو فی الفور کہیں گے جو کس نے پکڑا
اور کس نے دیکھا اور کون معائنہ واردات کا گواہ ہے.مگر ان مقدسوں کی نسبت کہ جن کی
راستبازی پر نہ ایک نہ دو بلکہ کروڑہا آدمی گواہی دیتے چلے آئے ہیں بغیر ثبوت معتبر اس امر کے
کسی کے سامنے انہوں نے مسودہ افترا کا بنایا یا اس منصو بہ میں کسی دوسرے سے مشورہ لیا یا وہ
راز کسی شخص کو اپنے نوکروں یا دوستوں یا عورتوں میں سے بتلا یایا کسی اور شخص نے مشورہ کرتے یا
راز بتلاتے پکڑا.یا آپ ہی موت کا سامناد دیکھ کر اپنے مفتری ہونے کا اقرار کر دیا.یونہی جھوٹی
تہمت لگانے پر تیار ہو جاتے ہیں.پس یہی تو سیاہ باطنی کی نشانی ہے اور اسی سے تو ان کی
اندرونی خرابی مترشح ہو رہی ہے انبیاء وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی کامل راستبازی کی قوی
حجت پیش کر کے اپنے دشمنوں کو بھی الزام دیا ایسا کہ یہ الزام قرآن شریف میں حضرت خاتم
الانبیا ﷺ کی طرف سے موجود ہے جہاں فرمایا ہے فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمُ عُمُرًا مِّنْ قَبْلِهِ عَ
أَفَلا تَعْقِلُونَ (سورۃ یونس الجزوا ) [ یونس : ۱۷] یعنی میں ایسا نہیں کہ جھوٹ بولوں اور افتراء
Page 152
الذكر المحفوظ
136
کروں.دیکھو میں چالیس برس اس سے پہلے تم میں ہی رہتا رہا ہوں کیا کبھی تم نے میرا کوئی
جھوٹ یا افترا ثابت کیا؟ پھر کیاتم کو اتنی سمجھ نہیں یعنی یہ سمجھے کہ جس نے کبھی آج تک کسی قسم کا
جھوٹ نہیں بولا.وہ اب خدا پر کیوں جھوٹ بولنے لگا ؟
براہین احمد یہ روحانی خزائن جلد اول صفحہ 107,108 ایڈیشن اول صہ 115 تا 117 )
پس تمام وہ لوگ جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا قریب سے مطالعہ کیا تھا، قطع نظر اس سے
کہ وہ دوست تھے یا دشمن، انہوں نے آپ کے سچا اور معتبر اور امین اور صادق ہونے کی گواہی دی.آج پندرہ سو
سال گزرنے کے بعد کسی خناس صفت کو یہ حق نہیں رہتا کہ وہ افق تاریخ کے جگماتے ہوئے اُس صدوق کی سچائی
اور اس امین کی دیانت داری پر انگلی اُٹھا سکے.تاریخ اُن سے یہ حق چھین چکی ہے اور ہمعصر مخالف رسول کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق فاضلہ کے کامل ہونے کی گواہی دے چکے ہیں.پس اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں
ہے کہ یہ گواہیاں تسلیم کی جائیں جیسا کہ بہت سے مؤرخین نے تسلیم بھی کیں.پھر دعوی سے بعد کی زندگی بھی گواہ ہے کہ ہر قسم کے حالات پیش آمدہ میں آنحضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم
دیانت داری اور صداقت کے پہلو پر تمام تر شرائط کے ساتھ کار بند رہے.آپ کی سیرت کا مزید مطالعہ کرنے
سے مزید روشن ثبوت ملتے ہیں.آپ کو ہر طرح کے حالات سے گزرنا پڑا مگر آپ نے ایک لمحہ کے لیے بھی اس
مقصد اعلیٰ سے منہ نہ پھیرا جس کی خاطر آپ مبعوث کیے گئے تھے.آپ نے ہر قسم کی آسائش کوٹھکرا دیا اور ہر قسم کی
بڑی سے بڑی تکلیف کا بھی مقابلہ کیا.ذیل میں ہم ان دونوں انتہاؤں کا الگ الگ ذکر کرتے ہیں تا کہ یہ
حقیقت واضح ہو کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام الہی کی حفاظت اور اس الہی امانت کو بحفاظت بنی نوع کے
سپرد کرنے میں کس درجہ جانفشانی سے کام کیا چنانچہ:
آنحضور ﷺ نے ہر قسم کی آسائش کو رڈ کر دیا اور قرآن میں کوئی رد و بدل قبول نہ کیا
چالیس بھی طرح طرح کی تھیں تا کہ کسی طرح آپ
صلی اللہ علیہ والہ وسلم اس پیغام کو بدل دیں.یہ مشہور واقعہ
بھی کس کے علم میں نہیں کہ کفار قریش کے سرکردہ افراد ایک گروہ کی صورت میں حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کے چچا حضرت ابو طالب کے پاس آئے اور عرض کی کہ محمد ( رسول اللہ ﷺ کو مجبور کیا جائے کہ وہ ہمارے
معبودوں کو بُرا بھلا نہ کہے.اس کے بدلہ میں ہم اسے حکومت میں حصہ دار بنا سکتے ہیں یا اگر دولت چاہتا ہے تو
جتنی چاہے ہم اس کے قدموں میں ڈھیر کر دیتے ہیں.عورت چاہیے تو اشارہ کرے عرب کی اعلیٰ حسب ونسب
والی خوبصورت ترین عورت حاضر کر دیتے ہیں.بس ہمارے بتوں کو غلط کہنا چھوڑ دے.اگر ان میں کوئی بات
نہیں مانتا تو صرف اتنا کریں کہ اپنی پناہ کے دائرہ سے نکال دیں.ایک پل کو ٹھہر کر غور کیجیے.یہ پیش کش معمولی
Page 153
قرآن کریم میں تحریف کے الزامات کے جواب
137
نہ تھی ذرا سوچیں کہ ایک امی بے کس ، جس کا نہ کوئی جتھا تھا اور نہ ہی گھرانے کی طاقت میں سے کچھ حصہ رکھتا
تھا.جس نے اعلیٰ مقامات پانے کے لیے اس وقت کے دستور کے مطابق ظلم اور تعدی کا کوئی رستہ اختیار نہ کیا
تھا.آج ظاہری لحاظ سے اس کی اکلوتی پناہ گاہ بھی چھن رہی تھی.ایک بوڑھا سہارا تھا جو آج لغزش میں تھا.دنیاوی شان و شوکت حاصل کرنے کا کوئی خواہش مند ہوتا تو ڈگمگا جاتا کہ اتنی دیر کی کاوشوں اور تکالیف کا آخر کار
شمرہ میل رہا ہے اور اُس دور میں اس سے بڑھ کر اور کسی فائدہ کی توقع کی جاسکتی تھی ؟ سرداری اور قیادت مل رہی
تھی.عزت و دولت مل رہی تھی.سردار زادی مل رہی تھی.یہ بھی سوچا جاسکتا ہے کہ اگر الہی پیغام پہنچانے کے
علاوہ بھی کوئی مقصد ہے تو اس کامیابی اور طاقت کے حصول کے بعد اس کی راہ اور آسان ہو جائے گی.سال ہا سال
کی تکالیف برداشت کرنے کے صلہ میں آج سب کچھ حاصل ہوتا دکھائی دے رہا تھا.اس سے زیادہ اور کیا
چاہیے؟ قیادت ، عزت، دولت اور اعلیٰ حسب و نسب کی عورت کا مطلب ہے ایک قبیلہ کی سیادت اور دوسرے
قبیلہ کی قیادت سے اہم باعزت تعلق اور اس کوٹھکرانے کا مطلب ہے کہ اب تک جو حاصل ہوا ہے وہ بھی ہاتھ
سے نکل جائے.اور دُنیاوی لحاظ سے دیکھیں تو اب تک کا حاصل تھا ہی کیا ؟ بوڑھا چچا ایک ہی کمز ور سہارا اور
وہ بھی اُس روز چھن رہا تھا.وہ بھی کہہ رہا تھا کہ تیرے اس رویہ سے میں کمزور اور بوڑھا اب اور بھی لڑکھڑا رہا
ہوں اور جو غریب صحابہ اب تک آپ کے ساتھ جمع ہوئے تھے اگر وہ بھی انہی دُنیاوی فوائد کے حصول کی خاطر جمع
ہوئے تھے تو اب وہ بھی تو چھوڑ چھاڑ کر چلے جاتے ، کہ ایک ہی موقع آیا اتنی مشکلات سے گزرنے کے بعد اور وہ
بھی گنوا دیا.کوئی بھی ادنی سی ادنی عقل کا انسان اگر ہوتا تو ضرور اس موقع سے فائدہ اُٹھاتا اور وہ تمام مقاصد
حاصل کر لیتا جس کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا.کیا ہی نادر موقع تھا قرآن کریم میں رد و بدل کر کے وہ کچھ نہ کہتے جو
مخالفین کے مذہبی جذبات کو انگیخت کرتا تھا.اب تو ان کا یہ مطالبہ بھی نہ تھا کہ سب کچھ بدل دیں.بس اتنا سا تو
مطالبہ تھا کہ ہمارے بتوں
کو بُرا نہ کہو.یہ آیات نکال دیتے اور سب کچھ مل جاتا.بلکہ آیات نکالنا بھی نہ پڑتیں
کیونکہ شیطانی آیات کے قصہ سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ سارے اختلافات ختم کرنے کے لیے بتوں کے
حق میں چھوٹا سا تعریفی کلمہ ہی کافی تھا.مگر آنحضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ہاتھ پر سورج اور ایک پر
چاند رکھ دو پھر بھی یہ ناممکن ہے.(بخاری کتاب المناقب باب قصۃ ابی طالب ) آنحضور اور آپ کے
صحابہ کی صداقت و دیانتداری اور ایمان
کی پختگی کا یہ ثبوت کیا ہی قوی ہے.اس وقت رسول کریم کو وہ تمام اشیا پل
رہی تھیں جو آج کل کے مغربی معاشرے میں پلنے والے مستشرق بیان کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ آپ نے ان کے
حصول کے لیے یہ سب سلسلہ شروع کیا تھا.پھر بھی ان کو قبول نہ کرنا بلکہ ایسا رستہ اختیار کرنا جس میں اب تک کا
تمام حاصل داؤ پر لگ رہا تھا، ایک واضح دلیل ہے کہ قرآن کو معین طور پر اور بعینہ اسی طرح پہنچانا جس طرح وہ
Page 154
الذكر المحفوظ
138
نازل ہوا تھا اور اپنی زندگی میں اس میں کوئی رد و بدل نہ ہونے دینا اور پھر ایسا انتظام کر دینا آپ کے نزدیک
سب سے زیادہ اہم تھا کہ کبھی بھی اس کلام میں کوئی دانستہ یا نا دانستہ رد و بدل یا تحریف راہ نہ پاسکے اور اس مقصد
کے حصول کے مقابلہ میں دُنیا کی شان و شوکت کی کوئی اہمیت نہیں تھی.یہ بھی سوچا جاسکتا تھا کہ جب یہ سب
شوکت اور طاقت حاصل ہو جائے گی تو اس مقصد کے حصول کی راہ آسان ہو جائے گی اور مومنین کی مشکلات بھی
دور ہو جائیں گی.پس یہ سب رڈ کرنا صرف دیانت داری کی مثال ہی نہیں بلکہ اس بات کا ثبوت بھی ہے کہ
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ میں سے کوئی بھی دنیاوی منفعت حاصل کرنے کی ذرہ بھر بھی نیت
نہیں رکھتا تھا اور آپ دھوکہ دہی سے حاصل کی گئی ظاہری شان و شوکت کو اپنے مقصد کے حصول کی خاطر استعمال
کرنے پر ہرگز راضی نہیں تھے.صرف اور صرف خدا تعالیٰ کی نصرت پر راضی تھے.یہ ایک پیغمبرانہ شان تھی.اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا مطالعہ کیا جائے تو انسان کی حیرت گم ہو جاتی ہے کہ یہ اعتراض
آخر کیا سوچ کر کیا جاتا ہے.ساری سوانح حیات کا مطالعہ کر لیں ! کہیں کوئی ایسا موقع نظر نہیں آتا کہ آپ نے دولت
جمع کرنے کی کوشش کی ہو.ایک ایک پل بتاتا ہے کہ کبھی دُنیا کے عیش و آرام سے شغف رہا ہی نہیں اور پھر پچیس سال
کی عمر میں حضرت خدیجہ سے شادی کے بعد آپ کو دولت کی کوئی کمی رہی بھی نہیں تھی.چنانچہ مخالفین بھی یہ تسلیم کرتے
ہیں کہ حضرت خدیجہ سے شادی کے بعد آپ ہر
قسم کے دُنیاوی فکروں سے آزاد ہو چکے تھے.لکھا ہے:
"...Orphaned at birth, he was always particularly
solicitous of the poor and the needy, the widow and the
orphan, the slave and the downtrodden.At twenty he
was already a successful businessman, and soon became
director of camel caravans for a wealthy widow.When
he reached twenty-five, his employer, recognizing his
merit, proposed marriage.Even though she was fifteen
years the older, he married her, and as long as she lived
remained a devoted husband.By forty this man of the desert had secured for
himself a most satisfying life: a loving wife, fine children
and wealth.(James A.Michener: Islam: The Misunderstood Religion,
Reader's Digest (American Edition) May 1955, p.68)
در یتیم جو ہمیشہ غریب اور نادار، بیوہ اور یتیم، غلام اور مسکین ،سب کی ہمیشہ حاجت روائی
کرنے پر کمر بستہ رہتا تھا.بیس سال کی عمر میں آپ ایک کامیاب تاجر کے طور پر ابھرے اور
جلد ہی ایک امیر خاتون کے اونٹوں کے قافلہ کے نگران بن گئے.جب آپ چھپیں سال کے
ہوئے تو آپ کی صلاحیتوں کو پہچانتے ہوئے اس خاتون نے ، آپ کو شادی کی پیشکش کی.
Page 155
قرآن کریم میں تحریف کے الزامات کے جواب
139
باوجود اس کے کہ وہ آپ سے پندرہ سال بڑی تھیں، آپ نے اُن سے شادی کر لی اور جتنا
عرصہ بھی ساتھ گزرا، آپ ایک وفا دار شوہر رہے.چالیس سال کی عمر تک صحرا کا یہ شہزادہ نہایت درجہ مطمئن زندگی گزار رہا تھا: ایک محبت
کرنے والی بیوی، اچھے بچے اور مال و دولت کی ریل پیل
شادی کے بعد کے پندرہ سالوں کی زندگی میں ایک ہی شغل نظر آتا ہے.وہ ہے غار حرا کی تنہائی میں
عبادت.کیا دُنیا اور دُنیا کے مال و متاع سے محبت کرنے والے انسان کا یہ وطیرہ ہوتا ہے کہ وہ دُنیا تیاگ کرسب
سے الگ تھلگ ہو جائے ؟ دنیا دار انسان تو اپنا کاروبار بڑھاتا ہے.دن رات اسی فکر میں غلطاں دوڑ دھوپ میں
لگارہتا ہے کہ کسی طرح مال و دولت حاصل کر لے.دُنیا داری میں اندھے بعض اوقات تو دولت کمانے کی دُھن
میں اپنے ہی گھر برباد کر دیتے ہیں اور چند روپوں کے لیے اپنی اور اپنے پیاروں کی زندگیاں بھی داؤ پر لگا دیتے
ہیں.مگر یہ کون سی دُنیا تھی جس کے آپ طلب گار تھے کہ دو مرتبہ ہاتھ آئی دولت ٹھکرا دی.پھر آپ کے کامیاب
تجارتی سفروں کو دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ اگر ذراسی بھی دُنیا طلبی ہوتی تو شادی کے بعد آپ بے حد ترقی کر سکتے
تھے.سرمایہ بھی موجود تھا، گھر کا سکھ بھی موجود تھا.خادم بھی موجود تھے اور سب سے بڑھ کر تجربہ بھی موجود تھا اور
صلاحیت تو آپ دکھا ہی چکے تھے کہ کاروبار کو ترقی دینے کی آپ کے اندر موجود ہے.مگر سب کچھ ہاتھ میں آنے
کے بعد سب چھوڑ دینا، معلوم ہوتا ہے کہ کچھ اور ہی مقصد تھا اور کوئی اور ہی جہان تھا جو آپ پیدا کرنا چاہتے تھے.تاریخ سے ثابت ہے کہ ہمیشہ مال و دولت کو اس طرح تقسیم کر دیا کہ اپنے لیے کبھی کچھ پس انداز نہ کیا.پس آپ
کے لیے دُنیا کے مال ددولت کی کوئی اہمیت تھی ہی نہیں اور جب حضرت خدیجہ سے شادی ہوئی تو پھر تو ناممکن تھا کہ
مزید کی طلب ہو.جو کچھ آچکا تھا وہ آپ کی ضروریات سے بہت بڑھ کر تھا اور اس کا ثبوت وہ سخاوت ہے جو
حضرت خدیجہ کے اپنا مال آپ کی خدمت میں پیش کرنے پر آپ نے دکھائی.پس آپ کی دُنیا سے بے نیازی اور بے رغبتی ، اور اس پر ضرورت سے بہت زیادہ مال اور محبت کرنے والے
اہل خانہ ایک پُرسکون زندگی گزار نے اور آپ کو دُنیا سے مزید بے نیاز کرنے کے لیے بہت تھا.آپ تو پہلی
دولت بھی لٹاتے پھر رہے تھے.بظاہر ہرقسم کی فکر سے آزاد اس پر سکون اور خاموش سے انسان کے لیے مزید کس
چیز کی ضرورت تھی جس کے لیے ساری قوم کی دشمنی مول لے لی؟ کیا ضرورت تھی جس کے لیے ایک مکمل طور پر
پُرسکون زندگی کو آپ نے چھوڑ دیا؟ اور پھر سیادت اور قیادت اور پہلے سے بہت بڑھ کر مال و دولت کی پیشکش،
در پیشکش بھی ایسی کہ جس سے مزید دنیاوی ترقیات کے دروازے کھل جاتے ،اس دور میں ایک دُنیا دار انسان
کے لیے طاقت اور قیادت اور دولت ہی تو آخری منزل ہے اور یہ سب کچھ آپ بار ہا ٹھکرا چکے تھے.پس دُنیا طلبی
اور
Page 156
الذكر المحفوظ
140
سے بہت بڑھ کر کوئی اور مقصد تھا جو آپ کو اس جدوجہد پر قائم رکھے ہوئے تھا اور ہر قسم کی دُنیاوی عزت اور
وجاہت اور مال و دولت کی پیشکش پر بھی آپ نے قرآن کریم سے اُن آیات کو نکالنا قبول نہ کیا جن میں غیر اللہ کی
پرستش سے منع کیا گیا ہے اور ان کی کمزوریاں ظاہر کی گئی ہیں.بلکہ جیسا کہ ذکر گز را کہ گزشتہ سطور میں درج
شیطانی آیات کا قصہ تو ظاہر کرتا ہے کہ کفار مکہ تو اتنے پر بھی راضی تھے کہ کچھ نہ نکالا جائے بس قرآن کریم میں ایک
دو آیات ہی اُن کے بتوں کی تعریف میں ڈال دی جائیں.وہ اسی پر خوش ہو کر سجدہ میں گر جاتے.پس اور کون سا
ایسا مرحلہ پیش آسکتا تھا کہ آپ قرآن کریم میں کوئی تحریف کر دیتے؟
یہاں پر مختصر طور پر یہ بھی بیان کر دینا غیر مناسب نہیں ہو گا کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اپنی فطرتی رحم دلی کی وجہ سے بنی نوع انسان کی نا گفتہ بہ حالت سے ناخوش تھے اور اس لیے معاشرتی اصلاح کے
لیے اپنی طرف سے معاشرتی مسائل کے حل کے طور پر یہ سب تعلیم گھڑی تھی.چونکہ وہ ایک انتہائی ذہین انسان
تھے اس لیے انہوں نے دُنیاوی حالات پر غور و خوض کر کے اس وقت کے مسائل کا یہ حل نکالا.پس قرآن کریم
آپ کے ذہن کی اختراع ہے نہ کہ کلام الہی (نعوذ باللہ ).یہ فلسفہ بگھارنے والوں کو سوچنا چاہیے کہ اگر ایسا تھا تو
پھر کیا یہ سب شان و شوکت اور قیادت اور طاقت حاصل کرنے کے بعد معاشرتی اصلاح میں پیش آنے والی
روکوں کو آسانی سے دور نہیں کیا جا سکتا تھا ؟ جو شخص خدا تعالیٰ کی طرف سے نہ ہو، وہ جب معاشرہ کی اصلاح کا بیڑا
اُٹھائے گا تو مدد کہاں سے حاصل کرے گا؟ ظاہری سی بات ہے معاشرہ سے ہی حاصل کرے گا.پھر کیوں پہلے یہ
غلطی کر دی کہ حضرت خدیجہ سے تحفہ حاصل ہوا مال غرباء میں تقسیم کر دیا اور پھر جب معاشرہ نے اتنی بڑی
پیش کش کی تو اسے ٹھکرا دیا؟ غزوہ حنین کے بعد مال کا ڈھیر
تقسیم کرتے کرتے اپنی چادر بھی لوگوں کو دے دی! کس
کے بھرو سے سب کچھ رد کر دیا؟ اگر خدا تعالیٰ کی پشت پناہی حاصل نہ تھی تو پھر ایک طاقتور حکومت بناتے اور اپنے
مقصد کے حصول کی خاطر اس مال کو حکومت کے فلاحی کاموں میں لگاتے.یہ سب کچھ ٹھکرا دینا تو بہت بڑی نادانی
تھی جس کی کسی ادنی سی عقل کے انسان سے بھی توقع نہیں کی جاسکتی.ایک طرف کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
بہت ذہین انسان تھے تو ایسی بے مثل تعلیم پیش کر دی جو گذشتہ الہی تعلیمات کو بھی مات دے گئی اور پھر اُس کلام کو
محفوظ رکھنے کا انتظام بھی ایسا اعلیٰ درجہ کا کر دیا کہ خدا تعالیٰ نے بھی اپنی کسی تعلیم کو محفوظ رکھنے کا ایسا انتظام نہ کیا.یوں گویا ( نعوذ باللہ ) اپنی ذہانت اور لیاقت سے خدا تعالیٰ کو بھی مات دے دی اور دوسری طرف آپ کی ذات
سے ایسی نادانی منسوب کرتے ہو.یہ بات بلاشبہ درست ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم سب عقلمندوں
سے بڑھ کر عقلمند تھے اور یہی عقل وخرد آپ کو یہ بجھاتی تھی کہ خدا تعالیٰ کے علاوہ کوئی محبوب ہستی ایسی نہیں ہوسکتی
جس کی خاطر سب دُنیا چھوڑ دی جائے.
Page 157
قرآن کریم میں تحریف کے الزامات کے جواب
141
آنحضرت مے نے ہر قسم کی تکلیف کا مقابلہ کیا مگر قرآن میں رد و بدل قبول نہ کیا
مندرجہ بالا سطور میں یہ حقیقت تو ثابت ہوگئی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے اس پیغام کی حفاظت اور
اس امانت کو بنی نوع تک پہنچانے کے لیے ایک عیش و عشرت والی زندگی کو ترک کرنا بھی گوارا کر لیا جو کہ کسی بھی
دُنیا دار کا خواب ہوتی ہے.مگر اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے.آپ نے اس مقصد کے حصول کے لیے نہ صرف
پُر آسائش زندگی کو ٹھکرایا بلکہ دوسری انتہاء کا بھی مقابلہ کیا یعنی ہر قسم کی تکالیف کا مقابلہ بھی کیا.کیا اپنے اور کیا
بیگانے سب آپ کی راہ کے کانٹے بن گئے.ریگزار عرب کا ذرہ ذرہ آپ کی مخالفت میں پہاڑ بن کر سامنے آتا
مگر آپ نے اولوالعزمی اور شجاعت اور مردانگی اور وقار و استقامت سے ان سب مشکلات کا مقابلہ کیا.ابولہب آپ
کا چچا آپ کی تبلیغی مہمات میں آپ کے پیچھے پیچھے یہ اعلان کرتا جاتا کہ نعوذ باللہ آپ پر
مرضِ جنون نے حملہ کر دیا ہے یا کبھی یہ کہ آپ پر جادو کر دیا گیا ہے.اس کی بیوی آپ کی راہ میں کانٹے بچھاتی.گلیوں بازاروں میں آپ کے خلاف ایک عام تحریک شروع ہوگئی.طائف کی سرزمین پر جو سلوک آپ کے ساتھ
کیا گیا وہ کس مستشرق کی نظروں سے پوشیدہ ہے؟ محاورۃ نہیں بلکہ حقیقہ سر سے لے کر پاؤں تک لہولہان
ہو گئے.خون جوتوں میں بھر گیا اور چلنا دو بھر ہو گیا.(بخاری کتاب بدء الخلق باب ذكر الملائكة )
جب آپ نے انعام واکرام، جاہ حشمت، سرداری، مال و دولت اور اعلی حسب و نسب والی خوبصورت عورت
سے شادی کی پیش کش کو ٹھکرادیا تو آپ نے اور آپ کے صحابہ نے یہ واضح کر دیا کہ یہ سلسلہ کسی دنیاوی لالچ یا طمع
کے لیے شروع نہیں کیا گیا تو پھر ایک دوسری انتہا مقابل پر کھڑی کر دی گئی ظلم وستم انتہا پر پہنچا دیا گیا.اس ظلم وسفا کی
کے دور کا ایک حصہ وہ تین سال ہیں جب آپ اور آپ کا ساتھ دینے والوں کو شعب ابی طالب میں محصور کر دیا
گیا.(بخاری کتاب وجوب الحج باب شعب ابی طالب) یہ سوشل بائیکاٹ کی ایسی بہیمانہ شکل
تھی کہ تاریخ عالم اس قسم کی دوسری مثال پیش کرنے سے قاصر ہے.بے سروسامانی اور فاقہ کشی کا شکار، بے بس
کمزور اور لاغر انسانوں نے تین سال تپتی گرمیاں اور ٹھٹھرتی سردیاں ایک پہاڑی گھاٹی میں گزاریں.لیکن کسی
کے پائے ثبات میں لغزش نہیں آئی.معترض بتا سکتا ہے کہ کونسی حرص دُنیا یا ہوا و ہوس تھی جس کی خاطر یہ لوگ اپنا
سب کچھ داؤ پر لگائے ہوئے تھے؟
پھر ایک دور ایسا بھی آیا کہ تمام ملکہ کے قبائل کے نمائندے آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے گھر کے باہر آپ کو
قتل کرنے کی نیت سے اکٹھے ہو گئے.یہ ہجرت کا مشہور واقعہ ہے.گزشتہ انبیاء کے ذریعہ آنے والے عالمی نبی
کے بارہ میں یہ عہد لیا گیا تھا کہ تُؤَزِرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ (الفتح : 10 ) یعنی اس کی مدد کرنا اور اس کی عزت کرنا.مگر
Page 158
الذكر المحفوظ
142
اہل مکہ مسلسل اس عہد شکنی کی مرتکب ہورہے تھے.اس صورت میں ان سے کیے گئے عہد پورے کرنا آپ کا فرض
نہیں ہوسکتا تھا.ہجرت کا وقت وہ وقت تھا کہ تمام سر دار مل کر اپنے اپنے قبیلوں کی نمائندگی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ
کی اس امانت میں خیانت کر رہے تھے اور آپ کو قتل کر کے اس سلسلہ کی جڑ کاٹ دینے کے درپے تھے.اس
وقت اہل مکہ اُس امین کے پاس اپنی امانتیں بھی رکھوائے ہوئے تھے.کوئی بھی ایسے موقع پر سارے کام بھول کر
اپنی زندگی بچانے کی فکر کرتا تو اس پر کوئی حرف نہیں آسکتا تھا.لیکن اس موقع پر اہل نظر نے کیا دیکھا ؟! آپ آن
کی امانتوں کی واپسی کی فکر میں غلطاں تھے.ایسے میں آپ نے حکم الہی کے سامنے سرجھکا دیا اور ہجرت کا مصمم
ارادہ کر لیا لیکن اپنے زیر سایہ پرورش پانے والے اور بہت ہی محبوب چچا زادعلی کو اپنے بستر پر لٹادیا تا کہ اگلے
دن لوگوں کی امانتیں بحفاظت واپس کر کے مدینہ آجائیں.(بخاری کتاب المناقب باب مناقب على )
کیا اس سے پہلے کوئی آنکھ ایسی خوش نصیب ہوئی ہے جو ایسا واقعہ دیکھنے کا دعویٰ کرتی ہو؟ کیا کوئی قوم ایسا قابل فخر
اور عظیم تاریخی واقعہ پیش کر سکتی ہے؟ نظر بار بار تاریخ کے صفحات سے تھکی ہاری لوٹ آتی ہے.ہاں ایک واقعہ ہے
جو صرف نوعیت کے لحاظ سے ہی کچھ مشابہ ہے مگر کیفیت میں کہیں کم ہے تاہم دیگر انبیاء کے ہجرت کے واقعات
کی نسبت رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی ہجرت کے واقعہ کے کچھ قریب ہے.ہم حضرت موسیٰ کے واقعہ کو
دیکھتے ہیں جو ہے تو ہجرت کا ہی لیکن حالات کی سنگینی اور خطرات کے لحاظ سے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ و
سلم کو پیش آنے والے واقعہ سے کہیں کم.کوئی موازنہ اور مقابلہ نہیں ہے لیکن تاریخ موازنہ کرنے کے لیے اور کوئی
ایسا واقعہ پیش ہی نہیں کرتی جو اس واقعہ سے بعینہ مشابہ ہو.اس لیے بامر مجبوری اسی کا انتخاب کرنا پڑتا ہے.حضرت
موسی کو بھی اپنی قوم کو ظلم اور ستم کی وجہ سے اہل ستم کی بستی سے نکال کر لے جانا پڑا.لیکن آپ نے کیا انتظام کیا؟
تو رات کے مطابق آپ نے اپنی قوم کو ی تعلیم دی کی زادراہ کے لیے اپنے مصری ہمسایوں سے
کسی نہ کسی بہانہ سے
عاریه زیور وغیرہ لو ( عہد نامہ جدید کتاب خروج باب 12 آیت 35,36 ) - تو رات کے مطابق خدا کا نبی اپنی قوم کو
امانتیں لے کر بھاگ جانے کا کہتا ہے.جبکہ ادھر کیا ہی حسین نمونہ ہے.زاد راہ مانگنے کا سوال ہی نہیں.مکہ کے
لوگ اس امین کے پاس اپنی امانتیں رکھوائے ہوئے ہیں.اسوہ موسوی تو ان امانتوں کو استعمال کرنے کی
اجازت دے رہا ہے مگر اسوہ محمدی کی رو سے سب سے بڑا مرحلہ ان امانتوں کو واپس کرنے کا ہے.حضرت موسیٰ
اکیلے نہیں تھے بلکہ قوم ساتھ تھی.ادھر حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ والہ وسلم کو اس رات گھر سے اکیلے نکلنا تھا.حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جان کا خطرہ نہیں تھا.رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم تنی ہوئی نی تلواروں کے محاصرہ
میں تھے لیکن ان امانتوں کی حفاظت کتنی عزیز تھی جو اس قوم کی تھیں جو کہ بذات خود الہی امانت میں خیانت کی مرتکب
ہورہی تھی.پھر انتظام بھی کیا خوب کیا کہ اپنے چچازاد کو اپنے بستر پر سلا دیا.جو آپ کے بیٹوں کی طرح تھا کیوں کہ
Page 159
قرآن کریم میں تحریف کے الزامات کے جواب
143
آپ کی آغوش میں پلا بڑھا تھا.جس سے آپ کی محبت کا اندازہ اس طرح ہوتا تھا کہ بعد میں آپ نے اپنی
محبوب بیٹی کے لیے اسے چھا.گویا امانت کی ادائیگی اپنی اور اپنے اعزاء و اقرباء کی جانوں سے بھی زیادہ عزیز
تھی.پس اس درجہ کا امانت دار انسان جو اپنے خون کے پیاسے دشمنوں کی امانتوں کے حق بھی اُن سے بڑھ کر ادا
کرنے والا تھا وہ کس طرح خدائی امانت میں خیانت کا مرتکب ہوسکتا تھا ؟ آپ کی زندگی کا یہ پہلو ہر شک کو نابود
کر دینے کے لیے کافی ہے کہ اس درجہ اعلیٰ اخلاق پر فائز انسان جو ادنی ادنی معاملات میں صداقت اور
دیانت کا دامن نہیں چھوڑتا اور اس کے لیے اپنی اور اپنے پیاروں کی زندگیاں بھی داؤ پر لگانے سے نہیں ہچکچاتا ،
کیسے ممکن ہے کہ الہی امانت میں خیانت کا مرتکب ہو جائے؟ ٹھہر کر غور کیجیے کہ جس دولت کو بے حیثیت قراردے
کر قدم قدم پر ٹھکرایا، جب وہ امانت کے طور پر آپ کے پاس آئی تو اس قدرا ہم ہوگئی کہ اپنی جان کے خطرہ کے
باوجود اس امانت کو اسکے اہل تک پہنچانے کا اہتمام کیا تو کس طرح ممکن ہے کہ جس الہی امانت کی اہمیت اپنی
اور اپنے پیاروں کی جانوں کی قیمت سے بھی زیادہ تھی جس پیغام کے لیے اتنی مشکلات برداشت کیں اور اپنی
جان پر کھیل کر اس کی حفاظت کی اور اپنے پیاروں کو مہیب خطروں میں ڈالا اور انکی جانیں تک اس امانت کی
حفاظت کی راہ میں قربانی کے لیے پیش کر دیں، جس کے لیے دُنیا کی جاہ و حشمت اور دولت و ثروت کی قربانی دی،
اس میں خیانت کے مرتکب ہو جاتے اور بعد میں کبھی رد و بدل کر دیتے؟ وہ تپتی دھوپ میں بھاری بھر کم پتھروں
کے بوجھوں تلے دبے ہوئے نڈھال جانثار، پیاس اور گرمی سے مونہوں سے باہر لٹکتی زبا نہیں، وہ کوئلوں پر زندہ
جلتے ، تڑپتے پیارے، وہ شہداء کے چرے ہوئے بدن، وہ انتہائی درندگی سے شہید کی گئی پردہ دار مقدس خواتین
کے لاشے، یہ سب تو رد و بدل اور تحریف نہ کرا سکے.پھر اور کون سی قیامت باقی تھی جو تحریف کا موجب ہو جاتی؟
پھر ایک مرتبہ وحی قرآن کی اشاعت ہو جانے کے بعد تو رد و بدل ہو ہی نہیں سکتا تھا کیونکہ جب وحی تحریری
صورت میں مشتہر ہوگئی ، حفظ کر لی گئی اور مسلمانوں میں عام ہوگئی تو پھر تو رد و بدل کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا.اس
وقت رد و بدل کرنا تو اس سلسلہ کی موت تھی.یہ تمام ثبوت دیکھ کر لا ز ما یہی نتیجہ نکالتا ہے کہ رسول کریم نے قرآن کو
بعینہ ویساہی ہم تک پہنچایا جیسا کہ آپ کو ملا تھا.قاری غور کرے کہ ایک طرف دولت مل رہی ہے اور دوسری
طرف انتہائی تنگ دستی اور مفلسی منہ کھولے کھڑی ہے.ایک طرف سیادت ہے اور دوسری طرف سماجی بائیکاٹ.یعنی ایک طرف معاشرہ آپ کو اپنے معزز ترین افراد میں شمار کر رہا ہے اور دوسری طرف آپ کو ایک ناکارہ عضو کی
طرح کاٹ کر پھینک دینے کی دھمکی دی جارہی ہے.ایک طرف عزت اور مرتبہ ہے اور دوسری طرف ہر شرف
سے محرومی.ایک طرف وطن کی سرداری ہے اور دوسری طرف جلا وطنی.ایک طرف اعلی حسب نسب کے با اختیار
خاندان سے رشتہ داری اور دوسری طرف مصائب میں پھنسے ادنی غلاموں سے دنیاوی اعتبار سے بظاہر
Page 160
الذكر المحفوظ
144
غیر منفعت بخش تعلق اور وہ تعلق بھی ٹوٹتا دکھائی دے رہا ہے اور غلام بھی ایسے جو خود پر بھی حق نہیں رکھتے تھے.ایک طرف اعلیٰ حسب ونسب اور طاقت کا حامل اپنا خاندان ہے، اور دوسری طرف ہر خاندان سے ناصرف قطع
تعلقی بلکہ ایک ایسے معاشرہ میں جہاں قبیلہ کے سہارے کے بغیر زندہ رہنے کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا تھا، تنہا
زندگی گزارنے کا المناک خوف.ایک عام شخص کے لیے جو ان نعمتوں سے پہلے ہی محروم ہو، ان سب نعمتوں کو
ٹھکرانا شائد اتنا مشکل نہ ہوتا جتنا آنحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے لیے تھا.کیونکہ آپ
کو یہ نعمتیں اور شرف
حاصل تھا.آپ معاشرہ میں بہت باعزت اور اعلیٰ اور بلند مرتبہ پر فائز تھے.اعلیٰ حسب ونسب والے خاندان
سے تعلق رکھتے تھے جو صدیوں سے علاقہ کا قائد اور سید تھا.پس ان سب نعمتوں کو چھوڑنا ایک آنے والی نعمت کا
چھوڑ نا نہیں تھا بلکہ اب تک جو کچھ بھی زندگی سے کمایا تھا اس سے محرومی تھی.اس ظلم اور تعدی، مشکلات اور
مصائب کے ہولناک دور میں اس طرح تمام تر عزت و مرتبت ، دولت و شرف، سیادت و قیادت کو ٹھوکر مار دینا اور
قرآن کے ایک ایک شعشہ کو سینہ سے چمٹائے رکھنا، کیا یہ سب ثابت نہیں کرتا کہ ہر قیمت چکانے والے یہ لوگ
ہرگز کوئی رد و بدل اور تحریف قبول نہیں کریں گے؟
گزشتہ صفحات میں کی گئی اس بحث کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زندگی بخش حسین و جمیل پیرایہ میں
دیکھیے.آپ فرماتے ہیں:
انبیاء کے واقعات عمری اور ان کی سلامت روشی ایسی بدیہی اور ثابت ہے کہ اگر سب
باتوں کو چھوڑ کر ان کے واقعات کو ہی دیکھا جائے تو ان کی صداقت ان کے واقعات
سے ہی روشن ہورہی ہے مثلاً اگر کوئی منصف اور عاقل ان تمام براہین اور دلائل صدق نبوت
حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اس کتاب میں لکھی جائیں گی قطع نظر کر کے محض
ان کے حالات پر ہی غور کرے تو بلا شبہ انہیں حالات پر غور کرنے سے اُن کے نبی صادق
ہونے پر دل سے یقین کرے گا اور کیونکر یقین نہ کرے وہ واقعات ہی ایسے کمال سچائی اور
صفائی سے معطر ہیں کہ حق کے طالبوں کے دل بلا اختیار ان کی طرف کھینچے جاتے ہیں.خیال
کرنا چاہیے کہ کسی استقلال سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دعویٰ نبوت پر با وجود پیدا
ہو جانے ہزاروں خطرات اور کھڑے ہو جانے لاکھوں معاندوں اور مزاحموں اور ڈرانے
والوں کے اول سے اخیر دم تک ثابت اور قائم رہے برسوں تک وہ مصیبتیں دیکھیں اور وہ دیکھ
اٹھانے پڑے جو کامیابی سے بکلی مایوس کرتے تھے اور روز بروز بڑھتے جاتے تھے کہ جن پر
صبر کرنے سے کسی دینوی مقصد کا حاصل ہو جانا وہم بھی نہیں گزرتا تھا بلکہ نبوت کا دعویٰ کرنے
Page 161
قرآن کریم میں تحریف کے الزامات کے جواب
145
سے از دست اپنی پہلی جمعیت کو بھی کھو بیٹھے اور ایک بات کہ کر لا کھ تفرقہ خرید لیا اور ہزاروں
بلاؤں کو اپنے سر پر بلالیا.وطن سے نکالے گئے.قتل کے لیے تعاقب کیے گئے.گھر اور
اسباب تباہ اور برباد ہو گیا.بار ہاز ہر دی گئی اور جو خیر خواہ تھے وہ بدخواہ بن گئے اور جو دوست
تھے وہ دشمنی کرنے لگے اور ایک زمانہ دراز تک وہ تلخیاں اٹھانی پڑیں کہ جن پر ثابت قدمی
سے ٹھہرے رہنا کسی فریبی اور مکار کا کام نہیں اور پھر جب مدت مدید کے بعد غلبہ اسلام کا
ہوا.تو ان دولت اور اقبال کے دنوں میں کوئی خزانہ اکٹھا نہ کیا.کوئی عمارت نہ بنائی.کوئی
بارگاہ طیار نہ ہوئی.کوئی سامان شاہانہ عیش کا تجویز نہ کیا گیا.کوئی اور ذاتی نفع نہ اٹھایا.بلکہ
جو کچھ آیا وہ سب قیموں اور مسکینوں اور بیوہ عورتوں اور مقروضوں کی خبر گیری میں خرچ ہوتا
رہا اور کبھی ایک وقت بھی سیر ہو کر نہ کھایا اور پھر صاف گوئی اس قدر کہ توحید کا وعظ کر کے
سب قوموں اور سارے فرقوں اور تمام جہان کے لوگوں کو جو شرک میں ڈوبے ہوئے تھے
مخالف بنالیا.یہودیوں سے بھی بات بگاڑ لی.کیونکہ ان کو طرح طرح کی مخلوق پرستی اور پیر
پرستی اور بداعمالیوں سے روکا.حضرت مسیح کی تکذیب اور توہین سے منع کیا جس سے ان کا
نہایت دل جل گیا اور سخت عداوت پر آمادہ ہو گئے اور ہر دم قتل کر دینے کی گھات میں رہنے
لگے.اسی طرح عیسائیوں کو بھی خفا کر دیا گیا.کیونکہ جیسا کہ ان کا اعتقاد تھا.حضرت عیسی کو نہ
خدا کا بیٹا قرار دیا اور نہ ان کو پھانسی مل کر دوسروں کو بچانے والا تسلیم کیا.آتش پرست اور
ستارہ پرست بھی ناراض ہو گئے.کیونکہ ان کو بھی ان کے دیوتوں کی پرستش سے ممانعت کی گئی
اور مدار نجات کا صرف تو حید ٹھہرائی گئی.اب جائے انصاف ہے کہ کیا دنیا حاصل کرنے کی
یہی تدبیر تھی کہ ہر ایک فرقہ کو ایسی ایسی صاف اور دل آزار باتیں سنائی گئیں کہ جس سے سب
نے مخالفت پر کمر باندھ لی اور سب کے دل ٹوٹ گئے اور قبل اس کے کہ اپنی کچھ ذرہ بھی
جمعیت بنی ہوتی یا کسی کا حملہ روکنے کے لیے کچھ طاقت بہم پہنچ جاتی سب کی طبیعت کو ایسا
اشتعال دے دیا کہ جس سے وہ خون کرنے کے پیاسے ہو گئے ؟ زمانہ سازی کی تدبیر تو یہ تھی
کہ جیسا بعضوں کو جھوٹا کہا تھا ویسا ہی بعضوں کو سچا بھی کہا جاتا.تا اگر بعض مخالف ہوتے تو
بعض موافق بھی رہتے.بلکہ اگر عربوں کو کہا جاتا کہ تمہارے ہی لات و عزمی بچے ہیں تو وہ تو
اسی دم قدموں پر گر پڑتے اور جو چاہتے ان سے کراتے.کیونکہ وہ سب خویش اور اقارب
اور حمیت قومی میں بے مثل تھے اور ساری بات مانی منائی تھی صرف تعلیم بت پرستی سے خوش
Page 162
الذكر المحفوظ
146
ہو جاتے اور بدل و جان اطاعت اختیار کرتے.لیکن سوچنا چاہیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم کا یکلخت ہر یک خویش و بیگانہ سے بگاڑ لینا اور صرف تو حید کو جو ان دنوں میں اس سے
زیادہ دنیا کے لیے کوئی نفرتی چیز نہ تھی اور جس کے باعث سے صدہا مشکلیں پڑتی جاتی تھیں
بلکہ جان سے مارے جانا نظر آتا تھا مضبوط پکڑ لینا یہ کس مصلحت دنیوی کا تقاضا تھا اور جبکہ
پہلے اسی کے باعث سے اپنی تمام دنیا اور جمعیت برباد کر چکے تھے تو پھر اسی بلا انگیز اعتقاد پر
اصرار کرنے سے کہ جس کو ظاہر کرتے ہی نو مسلمانوں کو قید اور زنجیر اور سخت سخت ماریں
نصیب ہوئیں کس مقصد کا حاصل کرنا مراد تھا؟ کیا دنیا کمانے کے لیے یہی ڈھنگ تھا کہ ہر
یک کو کلمہ تلخ جو اس کی طبع اور عادت اور مرضی اور اعتقاد کے برخلاف تھا؟ سنا کر سب کو ایک
دم کے دم میں جانی دشمن بنادیا اور کسی ایک آدھ قوم سے بھی پیوند نہ رکھا.جولوگ طامع اور
مکار ہوتے ہیں کیا وہ ایسی ہی تدبیریں کیا کرتے ہیں کہ جس سے دوست بھی دشمن
ہو جائیں؟ جو لوگ کسی مکر سے دنیا کو کمانا چاہتے ہیں کیا ان کا یہی اصول ہوا کرتا ہے کہ
بیکبارگی ساری دنیا کو عداوت کرنے کا جوش دلا دیں اور اپنی جان کو ہر وقت کی فکر میں ڈال
لیں.وہ تو اپنا مطلب سا دھنے کے لیے سب سے صلح کاری اختیار کرتے ہیں اور ہر ایک فرقہ
کو سچائی کا ہی ٹریفکیٹ دیتے ہیں.خدا کے لیے یکرنگ ہو جانا ان کی عادت کہاں ہوا کرتی
ہے خدا کی وحدانیت اور عظمت کا وہ کچھ دھیان رکھا کرتے ہیں.ان کو اس سے غرض کیا ہوتی
ہے کہ ناحق خدا کے لیے دکھ اٹھاتے پھریں ؟ وہ تو صیاد کی طرح وہیں دام بچھاتے ہیں کہ جو
شکار مارنے کا بہت آسان راستہ ہوتا ہے اور وہی طریق اختیار کرتے ہیں کہ جس میں محنت کم
اور فائدہ دنیا کا بہت زیادہ ہو.نفاق ان کا پیشہ اور خوشامد ان کی سیرت ہوتی ہے.سب سے
میٹھی میٹھی باتیں کرنا اور ہر ایک چور اور سادھ سے برابر رابطہ رکھنا ان کا ایک خاص اصول
ہوتا ہے.مسلمانوں سے اللہ اللہ اور ہندوؤں سے رام رام کہنے کو ہر وقت مستعد رہتے ہیں
اور ہر ایک مجلس میں ہاں سے ہاں اور نہیں سے نہیں ملاتے رہتے ہیں اور اگر کوئی میر مجلس دن
کو رات کہے تو چاند اور گیٹیاں دکھلانے کو بھی تیار ہو جاتے ہیں ان کو خدا سے کیا تعلق اور اس
کے ساتھ وفاداری کرنے سے کیا واسطہ اور اپنی خوش باش جان کو مفت میں ادھر ادھر کا غم لگا
لینا انہیں کیا ضرورت؟ استاد نے ان کو سبق ہی ایک پڑھایا ہوا ہوتا ہے کہ ہر ایک کو یہی بات
کہنا چاہیے کہ جو تیرا راستہ ہے وہی سیدھا ہے اور جو تیری رائے ہے وہی درست ہے اور جو تو
Page 163
قرآن کریم میں تحریف کے الزامات کے جواب
147
نے سمجھا ہے وہی ٹھیک ہے غرض ان کی راست اور ناراست اور حق اور باطل اور نیک اور بد
پر کچھ نظر ہی نہیں ہوتی بلکہ جس کے ہاتھ سے ان کا کچھ منہ میٹھا ہو جائے وہی ان کے حساب
میں بھگت اور سدھ اور جنٹلمین ہوتا ہے اور جس کی تعریف سے کچھ پیٹ کا دوزخ بھرتا نظر
آوے اس کو مکتی پانے والا اور سرگ کا وارث اور حیات ابدی کا مالک بنادیتے ہیں.لیکن
واقعات حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ والہ وسلم پر نظر کرنے سے یہ بات نہایت واضح اور
نمایاں اور روشن ہے کہ آنحضرت اعلیٰ درجہ کے یک رنگ اور صاف باطن اور خدا کے لیے
جان باز اور خلقت کے بیم و امید سے بالکل منہ پھیر نے والے اور محض خدا پر توکل کرنے
والے تھے کہ جنہوں نے خدا کی خواہش اور مرضی میں محو اور فنا ہو کر اس بات کی کچھ بھی پروانہ
کی.کہ تو حید کی منادی کرنے سے کیا کیا بلا میرے سر پر آوے گی اور مشرکوں کے ہاتھ سے
کیا کچھ دکھ اور درد اٹھانا ہوگا.بلکہ تمام شدتوں اور سختیوں اور مشکلوں کو اپنے نفس پر گوارا
کر کے اپنے مولیٰ کا حکم بجا لائے اور جو جو شرط مجاہدہ اور وعظ اور نصیحت کی ہوتی ہے وہ سب
پوری کی اور کسی ڈرانے والے کو کچھ حقیقت نہ سمجھا.ہم سچ سچ کہتے ہیں کہ تمام نبیوں کے
واقعات میں ایسے مواضعات خطرات اور پھر کوئی ایسا خدا پر توکل کر کے کھلا کھلا شرک اور
مخلوق پرستی سے منع کرنے والا اور اس قدر دشمن اور پھر کوئی ایسا ثابت قدم اور استقلال
کرنے والا ایک بھی ثابت نہیں.پس ذرہ ایمانداری سے سوچنا چاہیے کہ یہ سب حالات
66
کیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اندرونی صداقت پر دلالت کر رہے ہیں.“
( براہین احمد یہ روحانی خزائن جلد اول صفحہ 108 تا 110 ایڈیشن اول صہ 116 تا 121 )
اس گواہی کو تو منٹگمری واٹ جیسا متعصب انسان بھی تسلیم کرتا ہے.لکھتا ہے:
His readiness to undergo persecutions for his beliefs,
the high moral character of the men who believed in him
and looked up to him as leader, and the greatness of his
ultimate achievement-all argue his fundamental
integrity.(W.Montgomery Watt: Muhammad at Mecca; Oxford 1953, p.52)
آپ کا اپنے عقائد کی پاداش میں ہر قسم کی تکالیف اُٹھانے کے لیے تیار رہنا، آپ کے
پیروکاروں، جنہوں نے ہر موقع پر آپ سے راہنمائی لی کا اعلیٰ اخلاقی معیار اور آخر کار آپ کی
عظیم الشان فتح یہ تمام باتیں بنیادی طور پر آپ کے دیانت دار ہونے کی دلیل ہیں.
Page 164
الذكر المحفوظ
148
فتوحات کے بعد کی زندگی آنحضور کے رد و بدل نہ کرنے پر دلیل ہے
بعض مستشرقین یہ بھی کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے تمام اخلاق محض غلبہ اور کامیابی کے
حصول تک ایک دکھا وایا کامیابی حاصل کرنے کے لیے ایک ذریعہ اور ایک قسم کا اسلحہ تھے.اس لیے وہ وقت بھی تو
دیکھیں کہ جب آپ کو فتوحات ملنا شروع ہوئیں تو اس وقت آپ کا رویہ کیا تھا؟ کیونکہ اگر یہ سب کچھ محض غلبہ اور
حکومت حاصل کرنے کے لیے تھا تو پھر فتح کے بعد آپ کا رویہ بدل گیا ہوگا.آنحضور کی سوانح حیات کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی فتح کے بعد کی زندگی بھی اس وسوسہ کو ایسا دور
کرتی ہے کہ اس کی دھجیاں بھی نہیں ملتیں.چنانچہ جب آپ فاتح شہنشاہ کے روپ میں دُنیا کے سامنے آتے ہیں
تو اس وقت بھی آپ کے اخلاق کریمانہ آپ کے ہر فعل میں بدرجہ اتم نظر آتے ہیں.یہاں تک کہ غزوات
جیسے نازک مواقع پر بھی آپ کے اخلاق فاضلہ کی عمدہ مثالیں اسی آب و تاب سے سامنے آتی ہیں.فاتحسین عالم کے حالات پڑھ کر دیکھیے.حالت جنگ میں کہیں آپ کو آبادیاں ویران اور قلعے مسمار ہوتے
نظر آئیں گے تو کہیں انسانی لاشوں کے ڈھیر دکھائی دیں گے.کہیں انسانی کھوپڑیوں کے مینار نظر آئیں گے تو
کہیں عزت و عصمت کی بربادی کے قبیح اور قابل شرم نظارے.قرآن کریم جنگ کے بعد کے حالات کو ان الفاظ
میں بیان
فرماتا ہے:
قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةٌ وَّ
كَذلِكَ يَفْعَلُونَ) (النمل: 35)
یعنی جب بادشاہ فاتحانہ حیثیت سے کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے برباد کر دیتے ہیں
اور اس کے باعزت لوگوں کو ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں اور ایسا ہی کرتے چلے آئے ہیں.مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نازک مواقع پر اپنے عملی نمونہ سے جو عظیم درس دیے ان میں امانت،
بے مثل دیانت اور صداقت بھی شامل تھی.فتح خیبر کے موقع پر قلعہ ناعم کے ایک یہودی سردار نے آنحضرت کی
خدمت میں حاضر ہو کر بعض مسلمانوں کی شکایت کی کہ مسلمان ہمارے جانور ذبح کر کے کھا رہے ہیں، ہمارے
پھل اجاڑ رہے ہیں اور ہماری عورتوں پر بھی سختی کی جارہی ہے.دشمن ہونے کے باوجود یہ یہودی منصف مزاج
رسول اللہ سے انصاف کی توقع لے کر آیا تھا.پھر کیا نتیجہ نکلا ؟ کیا آنحضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے یہ جواب دیا
کہ ہم اس وقت حالت جنگ میں ہیں اور جنگ کا یہی دستور ہے؟ نہیں ! بلکہ آنحضرت سے اس یہودی کی یہ سچی
توقع پوری بھی ہوئی اور نبی کریم نے حضرت عبدالرحمن بن عوف سے فرمایا کہ گھوڑے پر سوار ہو کر یہ اعلان کریں
Page 165
قرآن کریم میں تحریف کے الزامات کے جواب
149
کہ جنت صرف مومنوں کو ملے گی نیز سب کو نماز کے لیے بلانے کا ارشاد فرمایا جب سب جمع ہو گئے تو آپ نے
فرمایا.بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ قرآن کریم میں حرام کر دیا ہے اس کے علاوہ کوئی چیز
حرام نہیں مگر یا درکھو اس کے علاوہ بھی مجھے اوامر و نواہی دیئے گئے ہیں.سنو! اللہ تعالیٰ تمہیں بلا اجازت اہل کتاب
کے گھروں میں داخل ہونے اور ان کے پھل کھانے کی اجازت نہیں دیتا جب کہ وہ اپنا حق ادا کر رہے ہوں جوان
کے ذمہ ہے.(زرقانی جلد ۲ صفحہ ۲۲۶)
بخاری کی حدیث کے مطابق واقعہ یوں ہے کہ جب آپ کو علم ہوا کے بعض لوگوں نے مال غنیمت کی تقسیم سے
قبل خیبر کے کچھ جانور پکڑ کر ذبح کر لیے ہیں اور ان کا گوشت پکایا جا رہا ہے آپ نے فوراوہ ہانڈیاں تو ڑ دینے اور
گوشت کو گرا دینے کا حکم دیا.(بخاری کتاب المغازی باب غزوة خيبر)
سنن ابی داؤد میں اس عظیم اسوہ کا ذکر ان الفاظ میں ملتا ہے:
عن عاصم بن كـلـيـب عن ابيه عن رجل من الانصار قال خرجنا مع
رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فاصاب الناسُ حاجة
شديدة وجهدًا فاصابُوا غَنَمًا فانتَهَبوها فَإِنَّ قُدُورَ نَا لَتُغْلَى إِذْ جَاءَ رَسولُ
الله صلى الله عليه وسلم يَمْشِي بِإِكْفَاءِ الْقُدور لِقَوْسِهِ ثم جَعَل يَرْمِلُ
اللَّحْمَ بِالتُّرابِ ثم قال إنّ النُّهْبَةَ لَيْسَتْ بِأَحَلَّ مِنَ الْمَيْتَةِ
( سنن ابی داؤد كتاب الجهاد باب في النهى عن النهبة اذا كان في الطعام...)
یعنی عاصم بن کلیب اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی بیان کرتے
تھے کہ ایک غزوہ میں ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے تو ایک موقعہ پر لوگوں کو بہت
سخت بھوک لگی اور سخت مصیبت میں مبتلا ہو گئے انہوں نے ایک بکریوں کا ریوڑ دیکھا اور اس
میں سے چند بکریاں پکڑلیں اور ذبح کر کے انکا گوشت پکا نا شروع کر دیا.گوشت ابھی ہانڈیوں
میں پک رہا تھا کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے.آپ نے آتے ہی اپنی کمان
سے ہماری ہانڈیوں کو الٹ دیا.آپ بوٹیوں کو مٹی میں مسلتے جاتے اور ساتھ ساتھ فرمارہے تھے کہ
لوٹ کا مال اسی طرح حرام ہے جیسا کہ مردار یا اس سے بھی بدتر ہے.کیا ہی عجیب نظارہ ہے فاتحین بھوکے ہیں اور مفتوح قوم آرام سے ہے.یوں آپ نے مسلمانوں
کے جذبات ، ان کی بھوک اور فاقہ کی قربانی تو دے دی لیکن مفتوح قوم کے اموال جن کی حفاظت کی ذمہ داری
اب آپ پر تھی، کماحقہ ادا کی اور امانت اور دیانت کو قربان کرنا گوارا نہ کیا.ساتھ ہی یہ سبق بھی دے دیا کہ اسلامی
جنگوں کی بنیاد محض خدا تعالیٰ کی رضا اور اس کے دین کی سربلندی ہے نہ کہ کوئی دنیوی منفعت.اس لیے کوئی مجاہد
Page 166
الذكر المحفوظ
150
کسی قسم کی دنیاوی یا ذاتی منفعت حاصل کرنے کا خیال بھی دل میں نہ لائے.فتح خیبر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی عظمت اخلاق کا حسین، روشن اور بلند تر مینار نظر آتا
ہے.اس واقعہ سے جہاں فاتحین عالم کے برخلاف محمد مصطفیٰ " کے خلق کی وہ عظیم الشان فتح نظر آتی ہے جو مفتوح
قوم کے ساتھ حسن سلوک عفو، رحم اور احسان سے عبارت ہے.وہاں آپ کے امین ہونے کا ایک روشن ثبوت
بھی ہے اور اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ آپ کے مد نظر کسی قسم کی ذاتی منفعت کبھی نہ تھی.فتوحات کا مقصد بھی
وہی تھا جس مقصد کے لیے آپ نے اندوہناک مظالم سہے تھے.ہمیشہ اپنی ذات کی نفی کی اور اسے اپنے اعلیٰ
مقصد کے حصول کی راہ میں کبھی حائل نہ ہونے دیا.ہر دو ادوار میں آپ کے مد نظر کوئی بھی دُنیاوی فائدہ نہ رہا.آپ کی سیرت کا بغور مطالعہ کرنے والے مخالفین بھی اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں اور کھلم کھلا بیان کرتے ہیں.فتح مکہ کا واقعہ کیا ہی عظیم الشان شہادت ہے آنحضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی صداقت پر اور اس بات پر کہ آپ
کا مقصد کوئی ذاتی یاد نیاوی نوعیت کا نہیں تھا اور اب بھی وہی مقصد تھا جو آپ اب سے 22 برس پہلے بیان فرماتے
تھے یعنی خدا کا پیغام لوگوں تک پہنچانا.چنانچہ جب مکہ فتح ہوا اور آپ کی جان کے دشمن بے بس ہو کر اور کٹی ہوئی خشک
ٹہنیوں کی طرح آپ کے قدموں میں ڈھیر ہو گئے تو آپ اب مکمل طور پر صاحب اختیار تھے کہ اپنے اور اپنے
جانثاروں پر ڈھائے گئے تمام مظالم کا بدلہ لے لیں.مگر آپ کے عام اعلان معافی نے یہ ثابت کر دیا کہ آپ
اپنے اور اپنے ساتھیوں پر کیے جانے والے مظالم کا انتقام لینے کے لیے نہیں آئے تھے.آپ کا مقصد تو خدا کے
دین کی فتح اور اشاعت تھی اور آج اس مقصد کے حصول کے رستہ میں حائل ایک بڑی روک دور ہو گئی تھی.یہ فتح تو
ایسی فتح تھی کہ آج تک اس کے نقارے اہل سماعت کے کانوں میں گونجتے اور انہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کی عظمت کا اعتراف کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں اور گواہ ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی ان سب
فتوحات کا مقصد ذاتی منفعت نہیں تھا بلکہ الہی پیغام کی اشاعت تھا اور آپ کبھی بھی اس پیغام کی حفاظت
اور پوری دیانت اور امانت کے ساتھ اس کی اشاعت سے غافل نہیں ہوئے.Stanley Lane-Poole آپ
کے مکہ میں کوٹنے کے مناظر بیان کرتے ہوئے اس یقین کا اظہار کرتا ہے کہ یہ فتح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
صرف اور صرف الہی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے استعمال کی اور کوئی ذاتی منفعت نہ حاصل کی.سٹینلی لین پول
کہتا ہے کہ یہ فتوحات انسانی نہیں ہوسکتیں اور کوئی دُنیاوی شہنشاہ کبھی ایسی فتوحات کا نظارہ نہ دکھا سکا اور نہ آئندہ
دکھا سکے گا.آپ کے کردار اور اخلاق کا ذکر کرنے کے بعد کہتا ہے کہ لازماً آپ خدا کے رسول تھے اور اس بات کا
آپ
کو دیگر تمام لوگوں سے زیادہ یقین تھا.(Stanley Lane-Poole: The Speeches and Table-Talk of the
Prophet Mohammad, London 1882, Introduction, pp.46,47)
Page 167
قرآن کریم میں تحریف کے الزامات کے جواب
151
اسلامی تاریخ ان مثالوں سے بھری پڑی ہے.وہ نظارہ بھی تو یاد کریں جب غزوہ حنین کے بعد مال غنیمت کی
تقسیم کے موقع پر نو مبایعین ( نئی نئی بیعت کر کے مشرف باسلام ہونے والوں ) میں سے کسی نے عدم تربیت کی
وجہ سے آپ کے ذاتی استعمال کی چادر بھی آپ کے بدن سے اُتار لی تھی.معلوم انسانی تاریخ میں کسی دُنیاوی
بادشاہ کا یہ نمونہ نظر نہیں آتا.اسی حقیقت کا اعتراف Washington Irving ان الفاظ میں کرتا ہے:
"His military triumphs awakened no pride nor vain
glory, as they would have done had they been effected
for selfish purposes.In the time of his greatest power he
maintained the same simplicity of manners and
appearance as in the days of his adversity.So far from
affecting a regal state, he was displeased if, on entering a
room, any unusual testimonials of respect were shown
to him.If he aimed at universal dominion, it was the
dominion of the faith; as to the temporal rule which
grew up in his hands, as he used it without ostentation,
so he took no step to perpetuate it in his family.(Washington Irving: Mahomet and his Successors, Printers:
George Bell & Son Londons, York St., Covet Garden, 1909,pg.199)
یعنی آپ (صلی اللہ علیہ والہ وسلم ) کی جنگی فتوحات نے نہ تو آپ میں کسی قسم کا تکبر پیدا کیا
اور نہ ہی نخوت جو کہ ذاتی غرض کے حصول کی خاطر حاصل کی گئی فتح سے پیدا ہوا کرتی ہے.اپنی
طاقت کے عروج پر بھی آپ نے اپنے اطوار میں اور ملنے جلنے میں وہی سادگی اور متانت برقرار
رکھی تھی جو کہ مصائب کے دور میں آپ کی شان تھی.شان وشوکت تو گجا ، آپ کے کمرے میں
داخل ہونے پر اگر کوئی خاص طور سے استقبال کرتا تو آپ اسے بھی ناپسند فرماتے.پس اگر کوئی
عالمی سلطنت آپ کے مد نظر تھی تو وہ محض عالم روحانی کی سلطنت تھی کیونکہ جو دنیاوی سلطنت
آپ کے ہاتھوں میں تھی اسے آپ نے کبھی بھی ظاہری شان و شوکت کے لیے استعمال نہیں کیا
اور نہ اسے اپنے خاندان میں جاری رکھنے کے لیے کوئی اقدامات کیے.کیا اس درجہ کا امانت دار انسان جو دشمنوں سے حالت جنگ میں بھی اخلاقیات کے انتہائی اعلیٰ نمونے دکھاتا
ہے، جو کسی قسم کی ذاتی یا دنیاوی منفعت کو اپنی بعثت کے مقصد کی راہ میں حائل نہیں ہونے دیتا.جو کمزوری اور
کسمپرسی کے ایام میں بھی کبھی اپنے مقصد سے غافل نہ ہوا اور اس کی فتوحات کے بعد کی زندگی بھی ایک عملی ثبوت
ہے کہ اس نے ان فتوحات سے کوئی ذاتی فائدہ نہ اٹھایا ، جو یہ دکھاتی ہے کہ اس کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف
پیغام الہی کی اشاعت تھی.صاف دکھائی دیتا ہے کہ کوئی حالات کی نرمی یا تنگی آپ کی توجہ اس مقصد سے پھیر نہ سکی
Page 168
الذكر المحفوظ
152
اور آپ اپنی بعثت کے مقصد کو کبھی نہ بھولے.پس آپ کی ساری زندگی گواہ ہے کہ ان فتوحات کے بعد بھی آپ
کے اخلاق
و کردار میں کوئی تبدیلی نہیں آئی بلکہ پہلے سے زیادہ اعلیٰ شان کے ساتھ دُنیا کے سامنے جلوہ گر ہوئے.پھر ایک اور پہلو سے دیکھیے کہ وہ انسان، جس نے اتنی تکالیف اُٹھانے اور اپنی زندگی کو داؤ پر لگانے کے باوجود
قرآن
کریم میں کوئی ردو بدل قبول نہ کیا.وہ جب فاتحانہ شان سے زندگی گزارتا ہے تو کیا اب اس خدائی امانت میں
خیانت کا مرتکب ہوسکتا ہے، جبکہ خوف اور کمزوری کی حالت بھی پہلے سی نہیں رہی تھی ؟ غور کیا جائے تو فتح کے بعد تو
کوئی بھی وجہ نظر نہیں آتی کہ کلام الہی میں کوئی تحریف کر دی جائے.جس پیغام کے لیے اتنی مشکلات برداشت کیں
اور اپنی جان پر کھیل کر اس کی حفاظت کی اور اپنے پیاروں کو مہیب خطروں میں ڈالا اور انکی جانیں تک اس امانت کی
حفاظت کی راہ میں قربانی کے لیے پیش کر دیں، جس کے لیے دُنیا کی جاہ و حشمت اور دولت و ثروت کی قربانی دی،
کیسے ممکن تھا کہ اس کے معاملہ میں کسی خیانت کے مرتکب ہو جاتے یا بعد میں
کبھی ردو بدل کر دیتے؟ وہ تپتی دھوپ
میں بھاری پتھروں کے بوجھوں تلے دبے ہوئے نڈھال جانثار، پیاس اور گرمی سے مونہوں سے باہر شکتی زبانیں ، وہ
کوئلوں پر زندہ جلتے ،تڑپتے پیارے، وہ شہداء کے چرے ہوئے بدن، وہ انتہائی درندگی سے شہید کی گئی پردہ دار مقدس
خواتین کے لاشے، یہ سب تو رد و بدل اور تحریف نہ کرا سکے.پھر اب فاتحانہ زندگی میں کون سی قیامت ٹوٹی تھی جو
تحریف کا موجب ہو جاتی ؟ معمولی سی سمجھ بوجھ والا انسان بھی بآسانی سمجھ سکتا ہے کہ مصائب اور مشکلات کے دور
کے بعد کسی سے مرعوب ہوئے بغیر قرآن کریم کی محافظت میں مد غلبہ حاصل ہو جانے کے بعد بلاوجہ مفتوح قوم کو
خوش کرنے کی خاطر کلام الہی میں تحریف کیونکر کر سکتا ہے؟ یہ تو ادنی سی عقل کے حامل انسان سے بھی بعید ہے کجا یہ کہ
اسے محمد ﷺ کی طرف منسوب کیا جائے.پس فتح کے بعد کے دور میں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی سیرت
اور حالات کا مطالعہ آپ کے بارہ میں تمام تر شکوک کو جڑھ سے اکھاڑ پھینکتا ہے.مندرجہ بالا بحث کا خلاصہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زندگی بخش الفاظ میں درج ہے.آپ فرماتے ہیں:
اسی غرض سے خدا تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوانح کو دو حصوں پر منقسم کر دیا.ایک حصہ دکھوں اور مصیبتوں اور تکلیفوں کا اور دوسرا حصہ فتحیابی کا.تا مصیبتوں کے وقت
میں وہ خلق ظاہر ہوں جو مصیبتوں کے وقت ظاہر ہوا کرتے ہیں اور فتح اور اقتدار کے وقت میں
وہ خلق ثابت ہوں جو بغیر اقتدار کے ثابت نہیں ہوتے.سو ایسا ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کے دونوں قسم کے اخلاق دونوں زمانوں اور دونوں حالتوں کے وارد ہونے سے کمال وضاحت
سے ثابت ہو گئے.چنانچہ وہ مصیبتوں کا زمانہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تیرہ برس تک مکہ
معظمہ میں شامل حال رہا.اس زمانہ کی سوانح پڑھنے سے نہایت واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ
Page 169
قرآن کریم میں تحریف کے الزامات کے جواب
153
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اخلاق جو مصیبتوں کے وقت کامل راستباز کو دکھلانے چاہئیں
یعنی خدا پر توکل رکھنا اور جزع فزع سے کنارا کرنا اور اپنے کام میں ست نہ ہونا اور کسی کے
رعب سے نہ ڈرنا ایسے طور پر دکھلا دیئے جو کفار ایسی استقامت کو دیکھ کر ایمان لائے اور شہادت
دی کہ جب تک کسی کا پورا بھروسہ خدا پر نہ ہو تو اس استقامت اور اس طور سے دکھوں کی
برداشت نہیں کرسکتا.اور پھر جب دوسرا زمانہ آیا یعنی فتح اور اقتدار اور ثروت کا زمانہ، تو اس زمانہ میں بھی
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق عفو اور سخاوت اور شجاعت کے ایسے کمال کے ساتھ
صادر ہوئے جو ایک گروہ کثیر کفار کا انہی اخلاق کو دیکھ کر ایمان لایا.دکھ دینے والوں کو بخشا اور
شہر سے نکالنے والوں کو امن دیا.ان کے محتاجوں کو مال سے مالا مال کر دیا اور قابو پا کر اپنے
بڑے بڑے دشمنوں کو بخش دیا.چنانچہ بہت سے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق
دیکھ کر گواہی دی کہ جب تک خدا کی طرف سے اور حقیقۂ راستباز ہو یہ اخلاق ہرگز دکھلا نہیں سکتا.یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے پرانے کینے یکلخت دور ہو گئے.آپ کا
بڑا بھاری خلق جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کر کے دکھلا دیا وہ خلق تھا جو قرآن شریف
میں ذکر فرمایا گیا ہے اور وہ یہ ہے.قُلْ اِنَّ صَلوتِی وَ نُسُكِي وَ مَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ
رَبِّ الْعَلَمِين [الانعام : 163] یعنی ان کو کہہ دے کہ میری عبادت اور میری قربانی اور میرا مرنا
اور میرا جینا خدا کی راہ میں ہے یعنی اس کا جلال ظاہر کرنے کے لیے اور نیز اس کے بندوں کے
آرام دینے کے لیے ہے تا میرے مرنے سے ان کو زندگی حاصل ہو.اسلامی اصول کی فلاسفی روحانی خزائن جلد 10 صفحہ 447 پانچواں سوال: زیر عنوان
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دوزمانے )
آنحضور نے کی صداقت کا ایک ثبوت آپ کا ایمان کامل
الوضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا اپنے اوپر نازل ہونے والی تعلیم پر کامل ایمان اس بات کا ثبوت ہے کہ
جبکہ آپ قرآن کریم کو خدا تعالیٰ کی طرف سے یقین کرتے تھے آپ اس میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتے تھے.اللہ
تعالیٰ قرآن کریم میں آنحضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے غیر متزلزل ایمان کے بارہ میں فرماتا ہے : آمَنَ الرَّسُولُ
بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ (البقرة : 286 ) کہ سب سے پہلے اپنے پر نازل ہونے والی تعلیم پر خود رسول
کامل ایمان لایا اور مومن بھی.چنانچہ اس حوالہ سے جب آپ کی سوان پر نظر دوڑائیں تو حضرت ابوطالب کے پاس
Page 170
الذكر المحفوظ
154
آکر سرداران عرب
کا یہ مطالبہ کرنا اسلامی تاریخ کے کس طالب علم سے پوشیدہ ہے کہ اپنے بھتیجے سے کہو کہ صرف
ہمارے بتوں کو بُرا بھلا کہنا چھوڑ دے.پس باوجود بار بار اصرار کے رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم فرماتے کہ جو
کچھ بھی نازل ہوتا ہے میں اسے بعینہ بیان کرنے کا پابند ہوں کیوں کہ یہ خدا کا کلام ہے.میں اس میں کوئی کمی
بیشی کر سکتا ہوں اور نہ ہی اسے بدل سکتا ہوں.(سیرۃ ابن ہشام باب مباداۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم قومہ
و ما کان منہم ) اور نہ ہی یہ ممکن تھا کہ خدا اسے بدل دے کیوں کہ کسی کا خوف یا نا پسندیگی اسے اپنا کلام بدلنے پر
مجبور نہیں کر سکتی.پھر خدا تعالیٰ نے جو کچھ نازل فرما دیا تھا وہ حتمی تھا اور خدا کی شان کے خلاف ہے کہ وہ بار بار اپنا
کلام بدلتا پھرے کیوں کہ وہ علیم اور خبیر ہے.وہ جو بات بھی پہلی بار کرے گا وہ لازماً درست ہوگی اور کم عقل
انسان کی طرح اسے اپنے کلام کی نظر ثانی کی ضرورت نہیں.ذرا شعب ابی طالب کی تکالیف ، اہل طائف کا ظلم، جانثاروں کی اندوہناک تکالیف کو ذہن میں دہرائیے
اور پھر فتح مکہ کے دوران بلند کیے جانے والے نعرہ لاَ تَشْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ “ (یوسف:93) پر غور کیجیے.کیا یہ واضح نہیں ہو جاتا کہ آپ اور آپ کے صحابہ ان تمام مظالم کا انتقام خدا کے حوالے کرتے اور تمام فتوحات کو خدا
تعالیٰ ہی کی طرف پھیرتے تھے؟ کیا تاریخ اس بات کا روشن ثبوت نہیں کہ ان فتوحات سے ذاتی انتقام یا ذاتی منفعت
حاصل کرنا کبھی بھی مد نظر نہیں رہا تھا؟ کیا یہ یقین نہیں ہوتا کہ آپ کا یہ تمام مظالم سہنا کسی اعلیٰ مقصد کے لیے تھا؟
ورنہ دنیاوی جنگی دستور کے مطابق ضرور انتقام لیتے اور وہی سلوک مخالفین سے روار کھتے جومخالفین نے آپ سے اور آپ
کے جانثاروں سے روا رکھا.اہالیان طائف کا ظلم کون کھلا سکتا ہے؟ صحیح بخاری میں اس واقعہ کا ذکر کچھ یوں ملتا ہے:
حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ میں نے آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نبی کی
حکایت فرماتے ہوئے دیکھا.جس کو اس کی قوم نے لہولہان کر دیا تھا اور وہ اپنے چہرے سے
خون پونچھتے جاتے تھے اور دُعا کرتے جاتے تھے کہ اے خدا! میری قوم کو بخش دے.وہ نادان ہے.(بخاری استابة المرتدين باب اذا عرض الذي.........)
پھر ذرا ہجرت کے واقعہ پر نظر ڈالیے.جب دشمن تعاقب کرتا ہوا اس غار کے بالکل دہانے پر آکھڑا ہوا
جس میں آپ اپنے یار غار ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ موجود تھے.وہ اتنا قریب تھے کہ ان کی باتوں کی آواز میں
تک سنائی دے رہی تھیں.وہ کہہ رہے تھے کہ یا تو اس غار میں ہیں یا پھر آسمان پر چلے گئے ہیں.ان حالات میں
جبکہ دشمن آپ کے ٹھکانے پر پہنچ گیا اور حضرت ابو بکر آپ کی حفاظت کے خیال سے گھبرائے تب بھی آپ نے
انہیں تسلی دی کہ لَا تَحْزَنُ إِنَّ اللهَ مَعَنَا آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا تعالیٰ پر کامل تو کل کا عظیم الشان اسوہ
دکھایا جو آپ کی صداقت پر ایک بہت عظیم الشان گواہ ہے کہ آپ سر سے پاؤں تک اس یقین میں گندھے ہوئے
تھے کہ آپ خدا تعالیٰ کے سچے رسول ہیں اور خدا تعالیٰ کا یہ وعدہ یقیناً سچا ہے کہ وہ آپ کو بحفاظت مکہ سے نکال
Page 171
قرآن کریم میں تحریف کے الزامات کے جواب
لے جائے گا اور فاتح کی حیثیت سے لوٹائے گا.155
حضرت مصلح موعودرضی اللہ عنہ اس واقعہ کے بارہ میں فرماتے ہیں:
اللہ اللہ کیسا تو کل ہے.دشمن سر پر کھڑا ہے اور اتنا نزدیک ہے کہ ذرا آنکھ نیچی کرے اور دیکھ
لے لیکن آپ کو خدا تعالیٰ پر ایسا یقین ہے کہ باوجود سب اسباب مخالف کے جمع ہو جانے کے آپ
یہی فرماتے ہیں کہ یہ کیونکر ہوسکتا ہے.خدا تو ہمارے ساتھ ہے پھر وہ کیونکر دیکھ سکتے ہیں.کیا کسی ماں نے ایسا بچہ جنا ہے جو اس یقین اور ایمان کو لے کر دُنیا میں آیا ہو؟ یہ جرأت و
بہادری کا سوال نہیں بلکہ تو کل کا سوال ہے خدا پر بھروسہ کا سوال ہے.اگر جرأت ہی ہوتی تو
آپ یہ جواب دیتے کہ خیبر پکڑیں گے تو کیا ہوا، ہم موت سے نہیں ڈرتے.مگر آپ کوئی معمولی
جرنیل یا میدان جنگ کے بہادر سپاہی نہ تھے.آپ خدا کے رسول تھے اس لیے آپ نے نہ
صرف خوف کا اظہار نہ کیا بلکہ حضرت ابوبکر کو بتایا کہ دیکھنے کا تو سوال ہی نہیں ہے.خدا ہمارے
ساتھ ہے اور اس کے حکم کے ماتحت ہم اپنے گھروں سے نکلے ہیں.پھر ان کو طاقت ہی کہاں مل
سکتی ہے کہ یہ آنکھ نیچے کر کے ہمیں دیکھ سکیں.یہ وہ تو کل ہے جو جھوٹے انسان میں نہیں ہوسکتا.جو ایک پُر فریب دل میں نہیں ٹھہر سکتا.شاید کوئی مجنوں ایسا کر سکے کہ ایسے خطر ناک موقعہ پر بے پرواہ رہے.لیکن میں پوچھتا ہوں کہ
مجنوں فقدانِ حواس کی وجہ سے ایسا کہہ تو لے لیکن وہ کون ہے جو اس کے مجنونانہ خیالات کے
مطابق اس کے متعاقبین کی آنکھوں کو اس سے پھیر دے اور متعاقب سر پر پہنچ کر پھر اس کی
طرف نگاہ اُٹھا کر نہ دیکھ سکیں ؟
(سیرت النبی ﷺ از حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب ایڈیشن اول صفحہ: 68.69)
اسی ہجرت کے دوران پھر ایک مرتبہ دُنیا نے آپ کے ایمان کامل کا نظارہ دیکھا جو آپ کو اپنے اوپر نازل
ہونے والی وحی الہی پر تھا.جب غار حرا تک آ کرنا کام لوٹنے پر کفار مکہ نے آپ کی گرفتاری پر انعام مقرر کر دیا.اس انعام کے لالچ میں سراقہ بن مالک بن جعشم تعاقب کرتا ہوا کسی طرح آپ کے قریب آ پہنچا.حضرت ابوبکر
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے خیال سے پریشان ہو گئے اور بار بار مڑ کر پیچھے دیکھتے تھے.مگر اپنے رب
کے وعدوں پر کامل ایمان رکھنے والے ہمارے
کوہ وقار و متانت آقا بے فکر ہیں اور ایک بار بھی مڑ کر نہیں دیکھتے کہ کیا ما جرا
ہے بلکہ گاہے گاہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو تسلی دیتے تھے کہ گھبرانے کی بات نہیں خدا تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے اور
جس طرح اللہ تعالیٰ نے آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور حفاظت فرمائی، یہ دیکھ کر سراقہ کو بھی یقین ہو گیا کہ آپ
Page 172
الذكر المحفوظ
156
لاز مأخد اتعالیٰ کی طرف سے تائید یافتہ ہیں.وشی جس نے آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کے بعد
آپ
کی نعش مبارک کی بہیمانہ طور سے بے حرمتی کی تھی، جب مکہ فتح ہوا تو وہ مکہ سے بھاگ کر طائف چلا گیا.جب اہل طائف نے بھی اطاعت قبول کر لی تو وحشی کے لیے یہ بھی ما من نہ رہا.چنانچہ جب طائف والوں کا
وفد آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو وہ بھی ان کے ساتھ چلا آیا کیونکہ اسے بتایا گیا تھا کہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایلچیوں سے برا سلوک نہیں کرتے.جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تو وحشی ہے؟ اس نے جواب دیا جی ہاں.آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا
کیا تو نے حمزہ کو شہید کیا تھا؟ اس پر اس نے جواب دیا کہ تمام حقیقت حال کا آپ
کو علم ہو چکا ہے.آنحضور صلی
اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی معاف فرما دیا اور صرف یہ کہا کہ کیا تو یہ کر سکتا ہے کہ زندگی بھر میرے سامنے نہ آئے؟
(بخاری کتاب المغازى باب قتل حمزه)
صلح حدیبیہ کے زمانہ میں ایک دفعہ 80 آدمیوں کا ایک دستہ منہ اندھیرے جبل تنعیم سے اتر آیا.وہ لوگ چھپ کر
آنحضور ﷺ کوقتل کرنا چاہتے تھے.اتفاق سے یہ گرفتار ہو گئے مگر حضور نے ان کو چھوڑ دیا اور کچھ تعرض نہ کیا.(ترمذی ابواب تفسیر باب تفسير سورة (فتح)
اسی طرح ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک صحابی نے آپ سے پوچھا کہ آپ پر بڑھاپے کے آثار آرہے ہیں تو
آپ نے فرمایا کہ مجھے سورۃ ہود سورۃ النباء وغیرہ نے ہی بوڑھا کر دیا ہے چنانچہ سنن ترمندی میں لکھا ہے :
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ
شِبُتَ قَالَ: شَيَّبَتْنِي هُودٌ، وَالْوَاقِعَةُ وَالْمُرْسَلَاتُ، وَ عَمَّ يَتَسَاءَ لُوْنَ وَإِذَا
الشَّمْسُ كُوّرَتْ
(ترمذی ابواب تفسیر القرآن باب ومن سورة الواقعة)
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ
اے رسول اللہ ! آپ پر بڑھاپے کے آثار نظر آنے لگے ہیں.اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا: مجھے سورۃ ہود، سورۃ الواقعہ، سورۃ المرسلات، عَمَّ يَتَسَاءَ لُوْنَ (سورۃ النبا ) اور وَ إِذَا
الشَّمْسُ كُوّرَتْ (سورۃ التکویر ) نے بوڑھا کر دیا ہے.ان سورتوں میں ان قوموں کا ذکر ہے جنہوں نے شرارت کرتے ہوئے انبیاء کو جھٹلایا جس کی پاداش میں خدا
نے انہیں ہلاک کر دیا.پس ان واقعات سے کسی قدر اندازہ ہوتا ہے کہ رسول کریم کا اپنے منجانب اللہ ہونے پر
ایمان کس قدر غیر متزلزل تھا.اسی لیے تو اپنے بے پایاں جذبہ رحم کی وجہ سے اس غم میں غلطاں رہتے تھے کہ
Page 173
قرآن کریم میں تحریف کے الزامات کے جواب
157
گزشتہ رسولوں کو جھٹلانے کی پاداش میں جس طرح اقوام ہلاک ہوئیں اسی طرح ظلم اور شرارت کی راہ سے میری
تکذیب کرنے کی وجہ سے بھی دُنیا کی مختلف اقوام بھی ہلاک نہ کر دی جائیں.اور آپ
کا یہ ایمان اور یقین آخر دم تک قائم رہا کہ آپ پر نازل ہونے والا کلام بلاشبہ خدا تعالیٰ ہی کی طرف
سے ہے.اس یقین کی ایک مثال بہت عجیب ہے.اسی کلام الہی میں اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
سے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیری حفاظت فرمائے گا اور تو اپنی طبعی عمر پوری کرے گا اور کسی مخالف کوشش کے
نتیجے میں تیری وفات نہیں ہوگی اور نہ تجھے قتل کیا جا سکے گا.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:
وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ (المائدة:68)
یعنی اللہ تعالیٰ تجھے لوگوں سے بچائے گا
آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وعدہ کی صداقت پر کامل ایمان تھا.چنانچہ جنگ حنین کے موقع پر جب ایک
دفعہ اسلامی لشکر میں ابتری کے آثار پیدا ہوئے اور لشکر بکھر گیا.صرف گنے چنے چند جانثار آپ کے پاس رہ گئے
اس وقت ایک بے نظیر شجاعت اور مردانہ شان کے ساتھ آپ نے گھوڑے کو دشمن کی طرف ایڑ لگاتے ہوئے
بآواز بلند للکارا کہ:
انا النبي لا كذب
انا ابن عبد المطلب
(بخاری کتاب المغازی ابواب غزوه حنين)
یعنی میں خدا کا نبی ہوں اور ہرگز جھوٹا نہیں ہوں.ہاں میں ہی وہ نبی ہوں جو عبدالمطلب کا بیٹا ہے.اگر اپنی جان کی حفاظت کے الہی وعدے کی صداقت پر اپنے زندہ ہونے سے زیادہ یقین نہ تھا تو کیوں
میدان کارزار میں دشمنوں کے نرغے میں گھرے ہونے کے باوجود اور لشکر اسلام کے بکھر جانے کے باوجود آپ
اس شان سے دشمن کو اپنی صداقت کا اعلان کرتے ہوئے اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں؟ بہت سے واقعات ہیں جو
یہ بتاتے ہیں کہ آپ کو اپنے اوپر نازل ہونے والے کلام کے سچا ہونے کا کس قدر یقین تھا اور آپ ایمان کے کس
اعلیٰ درجہ پر فائز تھے.مثلاً رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی سوانح کا مطالعہ کرنے والوں کی نظر سے یہ بات
پوشیدہ نہیں کہ وفات کے وقت فی الرفيق الاعلی (بخاری کتاب المغازی باب مرض النبي و وفاته )
کا بطور دعا د ہراتے چلے جانا بھی یہی بتاتا ہے کہ آخر دم تک اپنے منجانب اللہ ہونے اور اپنی صداقت پر یہ یقین
قائم رہا.یہ گواہی اتنی مضبوط اور نا قابل تردید ہے کہ مخالفین کو بھی مانے پر مجبور کرتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ والہ وسلم
کا کردار رسول خدا کا کردار تھا اور ہر دور کی طرح موجودہ دور میں بھی محققین نے بلا امتیاز مذہب و عقیدہ اس
حقیقت کو کھلم کھلا تسلیم کیا ہے.جان ڈیون پورٹ کی گواہی ملا حظہ کیجیے.کہتے ہیں:
Page 174
الذكر المحفوظ
158
محمد (ﷺ) کو بلاشک وشبہ اپنے مشن کی سچائی پر یقین تھا.وہ اس پر مطمئن تھے کہ اللہ کے
فرستادہ ہونے کی حیثیت سے انہوں نے ملک
کی تعمیر واصلاح کی ہے.ان کا اپنا مشن نہ تو بے
بنیاد تھا اور نہ فریب دہی ، جھوٹ
اور افترا پرمبنی تھا بلکہ اپنے مشن کی تعلیم وتبلیغ کرنے میں نہ کسی
لالچ یا دھمکی کا اثر قبول کیا اور نہ زخموں کی دُکھن اور تکالیف کی شدتیں ان کی راہ کی رکاوٹ بن
سکیں.وہ مسلسل سچائی کی تبلیغ کرتے رہے.(John Davenport: An Apology for Mohammad and the Koran, p.52,53)
ڈاکٹر Marcus Dods لکھتے ہیں:
Certainly he had two of the most important
characteristics of the prophetic order.He saw truth about
God which his fellowmen did not see, and he had an
irresistible inward impulse to publish this truth.In respect
of this latter qualification, Mohammed may stand in
comparison with the most courageous of the heroic
prophets of Israel.For the truth's sake he risked his life, he
suffered daily persecution for years, and eventually
banishment, the loss of property, of the goodwill of his
fellow-citizens, and of the confidence of his friends; he
suffered, in short, as much as any man can suffer short of
death, which he only escaped by flight, and yet he
unflinchingly proclaimed his message.No bribe, threat or
inducement, could silence him.'Though they array against
me the sun on the right hand and the moon on the left, I
cannot renounce my purpose.' And it was this persistency,
this belief in his call, to proclaim the unity or God, which
was the making of Islam.(Dr.Marcus Dods: Mohammed, Buddha, and Christ, pg.17,18)
یقیناً آپ (ﷺ ) میں سلسلہ انبیاء کی دو بہت واضح خصوصیات موجود تھیں.(اول) آپ
نے خدا کے بارہ میں وہ سچائی دیکھی جو آپ کے ہمعصر نہیں دیکھ سکے اور دوسری یہ کہ ) ایک طبعی
اور بے ساختہ جذبہ کہ آپ اس حقیقت کی خوب اشاعت کر دیں.اس دوسری خصوصیت نے
آپ کو بنی اسرائیل کے جرات مند انبیاء کی صف میں لا کھڑا کیا.سچائی کی خاطر آپ نے اپنی
زندگی داؤ پر لگادی.سالہا سال تک بلا ناغہ ظلم و ستم برداشت کرتے رہے.جس کا انجام جلا وطنی
کی صورت میں ظاہر ہوا جبکہ آپ کو اپنی جائداد سے بستی والوں کی تائید اور دوستوں کے اعتماد
سے ہاتھ دھونا پڑا.غرض یہ کہ آپ نے اتنی تکالیف برداشت کیں جتنی کہ موت سے ورے کوئی
انسان برداشت کر سکتا ہے.ہجرت کر کے اپنی جان بچائی مگر پھر بھی کبھی اشاعت اسلام سے نہ
Page 175
قرآن کریم میں تحریف کے الزامات کے جواب
159
ر کے.کوئی دھمکی ، رشوت یا لالچ آپ کو خاموش نہ کر سکا.”میرے ایک ہاتھ پر سورج اور ایک
ہاتھ پر چاند بھی رکھ دو تو بھی میں اپنے مقصد سے نہ ہٹوں گا یہ تھا آپ کا استقلال اور اپنے اوپر
نازل ہونے والی وحی پر ایمان کہ خدا کی توحید کی طرف بلایا جائے.جو کہ اسلام کی بنیاد بنا.سٹینلی لین پول رقم طراز ہیں:
He was the messenger of the one God, and never to
his life's end did he forget who he was or the message
which was the marrow of his being.He brought his
tidings to his people with a grand dignity sprung from
the consciousness of his high office together with a most
sweet humility...(Stanley Lane-Poole: The Speeches and Table-Talk of the
Prophet Mohammad, Introduction, pp.27-30.)
صل الله
وہ واحد و لاشریک خدا کے رسول تھے (ﷺ) ، اور تادمِ واپسیں کبھی بھی وہ اپنی اس
شناخت اور اپنے پیغام کی اہمیت کو نہیں بھولے.انہوں نے ایسے اعلیٰ طریق اور عظمتِ کردار
کے ساتھ خوشخبریاں اور بشارتیں اپنی قوم کو دیں جس کے ساتھ ایک میٹھا انکسار بھی شامل تھا.رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے خدا پر ایمان کو دیکھتے ہوئے MAJOR A.LEONARD لکھتے ہیں:
If ever any man on this earth has found God; if ever
any man has devoted his life for the sake of God with a
pure and holy zeal then, without doubt, and most
certainly that man was the Holy Prophet of Arabia.(Islam, its Moral and Spiritual Values, p.9; 1909, London)
اگر روئے زمین پر بسنے والے کسی شخص نے خدا کو پایا ہے؛ اگر کسی شخص نے
کبھی حقیقی طور
خالص اور پاکیزہ جذبہ کے ساتھ خدا کے لیے اپنی زندگی وقف کی ہے، تو بلا شبہ اور تمام تر وثوق کے
ساتھ وہ ایک شخص مقدس نئی عربی ( )
W.Montgummy Watt اپنے تمام تر تعصب کے باوجود لکھتا ہے:
Had it not been for his gifts as seer, statesman, and
administrator and, behind these his trust in God and
firm belief that God had sent him a notable chapter in
the history of mankind would have remained unwritten.(Mohammad At Madina Page 336)
(ترجمہ از اسوہ انسان کامل ) غیب پر اطلاع پانے ، مدبر اور منتظم ہونے کے علاوہ اگر آپ کا
اس بات پر محکم ایمان نہ ہوتا کہ خدا نے آپ کو بھیجا ہے تو انسانی تاریخ کا ایک قابل ذکر باب
Page 176
الذكر المحفوظ
160
ضبط تحریر میں آنے سے رہ جاتا.پھر اس پہلو سے بھی آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کامل کا مشاہدہ کیجیے کہ قرآن کریم کے بارہ میں آپ کا
رو یہ اس رویہ سے بالکل مختلف دکھائی دیتا ہے جو آپ کا اپنے اقوال کے بارہ میں تھا.جہاں تک اپنے کلام کا تعلق ہے
تو اگر کسی معاملہ کا آپ کو علم نہ ہوتا تو کھل کر اپنے اصحاب سے کہ دیتے اور اگر بشری کمزوری کی وجہ سے آپ سے کبھی
دُنیاوی اعتبار سے کسی معاملے میں غلطی ہوئی تو آپ نے کھل کر اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور فرمایا کرتے انتم اعلم
بامور دنياكم (بخاری کتاب التفسير باب هل كنت الا بشرا رسولا ) یعنی تم اپنے دنیاوی معاملات میں مجھے زیادہ
صاحب علم ہو لیکن جہاں تک قرآنی وحی کا تعلق ہے تو اس کے بارہ میں کبھی تر دنہ ہوا کہ اس میں کوئی کمی بیشی ہوگئی ہے
اور کبھی کلام الہی کو نہیں بدلا.یہ شان انسانی طاقت سے بالا ہے اور بلاشبہ پیغمبرانہ شان ہے.واضح نظر آتا ہے کہ
قرآن کریم کو آپ واقعی الہی کلام یقین کرتے تھے اور اسے اپنے کلام سے الگ اور بالا اور ممتاز سمجھتے تھے.انسان روز
مرہ معاملات میں غلطی کے امکان کو پیش نظر رکھتا ہے اور اسی بشری کمزوری کی وجہ سے نظر ثانی کی ضرورت ہمیشہ باقی
رہتی ہے اور رسول
کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کوبھی اپنے روز مرہ معاملات میں اسکی ضرورت پڑی جس کی مثالیں ملتی
ہیں.مگر قرآن کریم براہِ راست خدا تعالیٰ کا کلام ہونے کی وجہ سے اس بشری کمزوری سے پاک اور بالا رہا.یہ اس
بات کا بہت روشن ثبوت ہے کہ قرآن کریم بشری کاوش نہیں ہے ورنہ بار بار نظر ثانی اور تبدیلی کی ضرورت پڑتی.اسی طرح قرآن کریم کی کتابت کے بیان میں یہ ذکر بھی گزر چکا کہ آپ قرآنی وحی لکھنے کی تلقین فرمایا کرتے
تھے جب کہ اس کے برعکس اپنے ارشادات اور اقوال کو لکھنے سے منع فرما دیا تھا تا کہ آپ کے اقوال قرآن کریم
کے متن کے ساتھ مل نہ جائیں.بلکہ ایک دفعہ تو جلانے کا حکم بھی دیا.یہ طرز عمل بھی واضح کرتا ہے کہ آنحضور صلی
اللہ علیہ والہ وسلم اپنے کلام میں اور اس کلام میں جو کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے آپ پر نازل ہوتا تھا فرق کرتے تھے
اور جو عزت اور تکریم آپ کلامِ الہی کو دیتے تھے اور جس خصوصیت سے اس کی حفاظت کا التزام فرماتے تھے وہ
خصوصیت اپنے کلام کو ہر گز نہیں دیتے تھے.یہاں یہ ذکر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے فرمودات بھی نفسانی کلام نہیں
ہوتے تھے بلکہ یہ بھی الہی راہنمائی کے مطابق ہی ہوتے تھے اس امر کی گواہی اللہ تعالیٰ ان الفاظ میں دیتا ہے.وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ٥
ذُومِرَّةٍ ط فَاسْتَوَى (النجم : 4 تا 7)
ترجمہ: اور وہ خواہشِ نفس سے کلام نہیں کرتا.یہ تو محض ایک وحی ہے جو اُتاری جارہی ہے.اسے مضبوط طاقتوں والے نے سکھایا ہے.(جو) بڑی حکمت والا ہے.پس وہ فائز ہوا.
Page 177
قرآن کریم میں تحریف کے الزامات کے جواب
161
قرآن کریم کے متن کو اپنے اقوال سے بالا اور ممتاز رکھنے کی اس کوشش اور طرز عمل کے مشاہدہ سے غیر مسلم
مغربی محققین بھی چونک اٹھے ہیں:
Dr.Maurice Bucaille لکھتے ہیں:
Finally, It must be pointed out that Muhammad's
own attitude was quite different towards the Qur`an
from what it was towards his personal sayings.The
Qur`an was proclaimed by him to be a divine
Revelation.Over a period of twenty years, the Prophet
classified its sections with the greatest of care, as we
have seen.The Qur`an represented what had to be
written down during his own lifetime and learned by
heart to become part of the liturgy of prayers.The
hadiths are said, in principle, to provide an account of
his deeds and personal reflections, but he left it to others
to find an example in them for their own behaviour and
to make them public however they liked.(The bible The Quran and Science (translation from French by
Alastair D.Pannel and The Ahthor)Under Heading Conclusions
Pg 250-251)
بالآخر یہ واضح رہے کہ محمد (ﷺ) کا قرآن کریم کے بارہ میں رویہ اس رویہ سے بالکل
مختلف تھا جو کہ آپ کا اپنے فرمودات کے بارہ میں تھا.قرآن کریم کے بارہ میں آپ کا دعوی تھا
کہ یہ وحی الہی ہے.میں سال سے زائد عرصہ میں نبی (ع) نے بذات خود حد درجہ احتیاط کے
ساتھ اسے متعلقہ حصوں میں تقسیم کیا تھا جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں.قرآن وہ چیز ہے جو کہ رسول
کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی زندگی میں بطور خاص لکھا جاتا اور حفظ کر لیا جاتا تھا تا کہ فرض
نمازوں میں اس کی تلاوت کی جاسکے.جبکہ احادیث کے بارہ میں عمومی خیال یہ ہے کہ یہ آپ
کے روز مرہ افعال اور معمولات کا احاطہ کرتی ہیں.جن سے راہنمائی لینا اور لوگوں میں ان کی
اشاعت کرنا آپ نے دوسروں پر چھوڑ رکھا تھا کہ جیسے چاہے وہ کریں.اس موضوع پر جان ڈیون پورٹ کی گواہی درج کر کے اگلے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں.لکھتے ہیں:
ممکن ہے یہ سوچا جائے کہ وہ آدمی جس نے اتنی بہت سی اور تادیر قائم رہنے والی اصلاحات
کیں، انواع واقسام کی بُت پرستی کے بدلے، جس میں لوگ مدتوں سے مبتلا تھے، ایک خدا کی
عبادت کا داعی بنا.جس نے دختر گشی کی رسم فتیح کومٹایا.شراب اور دوسری نشہ آور اشیاء کوحرام
ٹھہرایا.جوئے کی ممانعت، نسبتاً ایک دائرہ میں رہتے ہوئے تعدد ازواج کو محدود کیا، وغیرہ
Page 178
الذكر المحفوظ
162
وغیرہ...کیا ہم یہ تصور کر سکتے ہیں کہ اس کا خدائی مشن اس کے ذہن کی محض اختراع تھی ؟ اور کیا
وہ جھوٹ کو جانتے بوجھتے نبھاتا رہا؟ نہیں! ہرگز نہیں! محمد (ﷺ) کو در حقیقت بچے مذہبی
ادراکات اور روحانی احساسات حاصل تھے جن کے سبب انہوں نے اپنے مشن کو انتہائی مستقل
مزاجی ، پامردی و استقلال سے آگے بڑھایا اور نہ اس کے جھٹلائے جانے کی پروا کی اور نہ اس کی
راہ میں مصائب و مشکلات کی.یہ سچائی ، یہ حق کی معرفت انہیں شروع سے آخر تک حاصل رہی
یعنی حضرت خدیجہ کے سامنے پہلی وحی کے نزول سے لے کر حضرت عائشہ کی باہوں میں
آخری سانس لینے تک.(John Davenport: An Apology for Mohammed and the Koran,
London: 1869.17.آنحضور ﷺ کی صداقت کا ثبوت صحابہ کا غیر متزلزل ایمان
صحابہ رضوان
اللہ علیہم اجمعین کا آنحضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم پر غیر متزلزل ، پختہ اور روز افزوں ترقی کرتا ہوا
ایمان بھی اس بات کا ایک ثبوت ہے کہ قرآن کریم بلاتحریف و تبدل اُن تک پہنچ رہا ہے.آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم
کی حیات طیبہ کا ایک ایک لمحہ اُن کے سامنے تھا اور وہ کامل طور پر اس ایمان پر قائم تھے کہ آپ جو کلام الہی ہم تک
پہنچا رہے ہیں وہ حرف بحرف وحی الہی ہے اور ہر قسم کے رد و بدل سے پاک ہے.ان کا ایمان اس بات کا گواہ
ہے کہ وہ دل کی گہرائیوں سے مانتے تھے کہ یہ سلسلہ خدائی ہے اور پوری دیانت داری اور حفاظت کے ساتھ ان
تک پہنچ رہا ہے تبھی تو ایمان کے ایسے اعلیٰ نظارے دکھائے جو عدیم النظیر ہیں.چنانچہ بے شمار واقعات ملتے
ہیں جن سے واضح ہو جاتا ہے کہ قرآن کریم کے معاملے میں صحابہ بہت زیادہ حساس تھے.قرآنِ کریم اور
رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم پر ایمان کا دارو مدار ہستی باری تعالی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کلام الہی کی
سچائی پر تھا.وہ اپنے سر دھڑ کی بازی اسی ایمان کی حرارت کی وجہ سے لگاتے تھے.ماؤں کے دلارے اور باپوں
کے سہارے، بہنوں کے پیارے اور بیویوں کے سہاگ اسی ایمان کی پختگی کی وجہ سے خدا کی راہ میں قربان
ہونے کو مچل رہے تھے.کیسے ممکن ہے کہ اتنے کامل ایمان والے تحریف کی کسی ادنیٰ سی کوشش پر بھی خاموش
رہتے.انہوں نے خدا تعالیٰ کے حضور مجسم قرآن صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے کیسے ہوئے وعدے سچ کر دکھائے تھے
کہ ہم آپ کے آگے بھی لڑیں گے اور پیچھے بھی، دائیں بھی لڑیں گے اور بائیں بھی اور کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک
نہیں پہنچ سکے گا جب تک کہ ہماری لاشوں کو نہ روند ڈالے.(بخاری کتاب المغازی باب اذ تستغيثون ربكم....)
اور اس شان سے یہ وعدے ایفا کیسے کہ جب بھی کوئی اس الہی پیغام کی حفاظت میں جان
کا نذرانہ پیش کرتا تو فُرتُ
Page 179
قرآن کریم میں تحریف کے الزامات کے جواب
163
الكَعْبَةِ کا نعرہ لگاتے ہوئے دُنیا چھوڑتا.(بخاری کتاب المغازی باب غزوة الرجيع...) اُن کے بارہ
میں خدا تعالیٰ نے یہ گواہی دی تھی کہ مِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَّنْتَظِر (الاحزاب:24) یعنی اُن میں
سے کچھ اپنے عہد پورے کر چکے ہیں اور کچھ منتظر ہیں کہ جانثاری کا موقع ملے اور عہد پورے کریں.کیونکہ انہیں
یقین تھا کہ ان سے کیے جانے والے تمام وعدے الہی ہیں اور ان میں کوئی بھی بشری دخل نہیں ہے.پس کس
طرح ممکن ہے کہ قرآن کریم کی حفاظت پر حرف آنے کے ادنیٰ سے شک پر بھی وہ خاموش رہتے ؟ وہ کہ جو مرتے
وقت یہ شعر پڑھا کرتے کہ:
فلست ابالی حین اقتل مسلما علی ای جـنـب كـان لله مصرعی
جبکہ میں مسلمان ہونے کی حالت میں قتل ہورہا ہوں تو مجھے پروا نہیں کہ خدا کی راہ میں، میں کس پہلو پر گرتا ہوں
و ذلك فى ذات الاله و ان يشاء يبارك على اوصال شلو ممزع
اور یہ شہادت تو باری تعالیٰ کی خاطر ہی ہے پس اگر وہ چاہے تو میں کٹ کر جس پہلو پر بھی گروں ہی میں وہ برکت ڈال دے گا
(بخاری کتاب المغازي فضل من شهد بدرا)
یہ وہی جانثار تھے کہ دورانِ قید جب انہیں یہ کہا گیا کہ کیا تمہارا دل نہیں کرتا کہ آج محمد (ﷺ) تمہاری جگہ
ہوتے اور تم چھین سے اپنے گھر میں بیٹھے ہوتے تو دشمنوں کے شکنجوں میں پھنسے ہوئے وہ عاشقانِ جانثار کس
طرح تڑپ کر کہتے کہ ہمیں تو یہ بھی منظور نہیں کہ ہم اپنے گھروں میں آرام سے ہوں اور رسولِ خداصلی اللہ علیہ وسلم
کے پاؤں میں راہ چلتے کوئی کانٹا بھی کچھ جائے.(بخاری کتاب المغازی فضل من شهد بدرا) ایک طرف دشمن کی
قید میں ایمان کا یہ نمونہ ہے کہ اپنی جان کے بدلہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں کانٹا چبھنا بھی
گوارا نہیں ہے اور دوسری طرف کیا نظارہ ہے، ذرا نظر دوڑائیں! بائبل میں یسوع کے اس حواری کا ذکر ملے گا
جس نے اپنی جان بچانے کی خاطر یسوع کو دشمنوں کے نرغہ میں بے بس اور لاچار، زخموں کی تکالیف سے بے
حال آہ و بکا کرتے دیکھا تو بھی اس کا ایمان جوش میں نہ آیا اور اس مشکل وقت میں بھی اس نے مسیح سے لا تعلقی کا
اظہار کر دیا.ان خاص الخاص حواریوں سے کہیں بڑھ کر وہ عورت، مریم مگدر لینی نکلی جو یسوع سے تعلق کا دم بھرتی
رہی اور اس
تعلق کی خاطر زمانہ کی پرواہ نہیں کی جو آج تک اس تعلق پر حیران ہے.حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا بستر مرگ پر بے قراری سے اس حسرت کا اظہار کرنا کہ میں تو جب بھی جنگ
کے میدان میں اترا شوق شہادت لے کر اترا لیکن یہ خواہش حسرت ہی رہی.میرے جسم پر کوئی حصہ ایسا نہیں جس
نے راہ اسلام میں زخم نہ کھایا ہو لیکن آج میں بے بس بستر مرگ پر پڑا جان دے رہا ہوں.ذرا تاریخ کے اوراق
چھانی اور دیکھیے کہ آنحضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے پیروکاروں کے علاوہ اور کس نبی کے پیروکاروں کی طرف سے خدا
Page 180
الذكر المحفوظ
164
کی راہ میں جان
قربان کرنے کی تمنا کا اس شدت اظہار اور پھر عملی نمونہ سے اس تمنا کو سچا کر دکھانا اور اپنے نبی پر اس
شان کے ایمان کا نمونہ ملتا ہے.ایمان تو کجا، بائبل کے مطابق تو موسی کی قوم نے چالیس سال صحرا میں دھکے کھانا
قبول کر لیا مگر موسی کی معیت میں خدا کی راہ میں آگے بڑھنے سے انکار کر دیا.یسوع کے خاص حواریوں میں سے
ایک حواری نے چند روپوں کے عوض جنت کی کنجیوں
کی کوٹھکرادیا اور یسوع مسیح کی مخبری کر کے انہیں گرفتار کرا دیا.پس کیسے ممکن تھا کہ جانوں کے نذرانے پیش کرنے والے صحابہ اسی خلق عظیم کی کتابی صورت میں کوئی ادنی سا
بھی بگاڑ یار ڈو بدل برداشت کر لیتے ؟ بہت سی مثالیں موجود ہیں کہ حفاظت قرآن کے بارہ میں ادنی ادنی سی غلط فہمی
پر وہ بھرے ہوئے شیروں کی طرح اُٹھ کھڑے ہوتے.کیا ابن وراق نے وہ واقعہ نہیں پڑھا کہ جب حضرت عمر
اسلام سے قبل غصہ کی حالت میں اپنی بہن کو مار رہے تھے.بہن
کا لہو دیکھ کر جب آپے میں آئے تو قرآن کے وہ
اوراق مانگے جو وہ پڑھ رہی تھیں.کس طرح وہ مظلوم عورت صاف انکار کر دیتی ہے کہ تم اس حالت میں قرآن کو
چھو بھی نہیں سکتے.اس تکلیف دہ چوٹ کے بعد بھی کہ جب لہو بہہ رہا تھا قرآن کی تکریم کس درجہ عزیز تھی.کس
طرح ممکن ہے اس درجہ ایمان پر فائز جاشار تحریف قرآن
کی کسی بھی کوشش پر خاموشی اختیار کرتے.پھر وہ واقعہ بھی ابن وراق کے علم میں ہوگا کہ حضرت عمرؓ کے سامنے ایک صحابی ہشام بن حکیم بن حزام نے
قرآن کی چند آیات اس انداز میں پڑھیں جو حضرت عمر کے نزدیک درست نہیں تھا.اس پر آپ ان کو چادر سے
پکڑے گھسیٹتے ہوئے آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے.اس وقت رسول
کریم نے فرمایا کہ عمر سے
جانے دو یہ درست پڑھ رہا ہے.(بخاری کتاب فضائل القرآن باب انزل القرآن على سبعة احرف)
اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود ایک آیت کو اور انداز میں سُن کر پڑھنے والے کو لے کر فوراً رسول کریم کی
خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ نے وہی فیصلہ فرمایا جو حضرت عمرؓ کے معاملہ میں فرمایا تھا(بخاری کتاب فضائل
القرآن باب اقرئوا القرآن ما ائتلف قلوبکم).صحابہ نے تو قدم قدم پر جانثاری اور اعلیٰ ایمان کے نظارے دکھائے :
حضرت بلال بن رباح رضی اللہ عنہ امیہ بن خلف کے ایک حبشی غلام جب ایمان لائے تو
امیہ ان کو دو پہر کے وقت جبکہ آسمان سے آگ برس رہی ہوتی اور مکہ کا پتھر یلا میدان بھٹی کی
طرح تپ رہا ہوتا ، باہر لے جاتا اور نگا کر کے زمین پر لٹا دیتا.بڑے بڑے گرم پتھر ان کے سینے
پر رکھ کر کہتا کہ لات اور عزملی کی پرستش کر اور محمد سے علیحدہ ہو جاور نہ اسی طرح عذاب دے کر مار
دوں گا.حضرت بلال زیادہ عربی نہ جانتے تھے.صرف اتنا کہتے احد احد یعنی اللہ ایک ہی
ہے.اللہ ایک ہی ہے.یہ جواب سن کر امیہ اور بھڑک اٹھتا اور ان کے گلے میں رستہ ڈال کر
Page 181
قرآن کریم میں تحریف کے الزامات کے جواب
165
انہیں شر یرلڑکوں کے حوالہ کر دیتا.وہ ان کو مکہ کے پتھر لے گلی کوچوں میں گھسیٹتے پھرتے جس سے
ان کا بدن لہولہان ہو جاتا مگر ان کی زبان سے سوائے احد احد کے اور کوئی کلمہ نہ ادا ہوتا.حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان پر ڈھائے جانے والے یہ ظلم وستم دیکھ کر ایک بڑی
قیمت دے کر انہیں خریدا اور آزاد کر دیا.(اسد الغابۃ زیر حالات حضرت بلال)
ہجرت کے ساتویں سال کے سفر کے وہ واقعات دیکھیں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم اپنے بعض رؤیا اور
کشوف کی بنا پر یہ سمجھے کہ اس سال مسلمان حج کر کے لوٹیں گے.صحابہ کس درجہ پر یقین تھے کہ وہ بیت اللہ کی زیارت
سے مشرف ہوں گے اور ایک ذرہ بھی ان میں شک کا عصر نہ تھا.کیا ایک جھوٹے کی بات سُن کر ایسا یقین ہوتا ہے؟ اس
وقت جب حج نہ ہوسکا تو شدید صدمہ کا شکار ہو گئے.حضرت عمرؓ نے یہی سوال اُٹھایا کہ کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں
اور اللہ کا وعدہ سچا نہیں؟ (بخاری کتاب المغازی باب غزوة الحديبية ) صلح حدیبیہ کے موقع پر الہی خبروں پر یقین
کرتے ہوئے صحابہ پورے طور پر متیقن تھے کہ وہ ضرور خانہ کعبہ کا حج کریں گے.مگر جب ایسا نہ ہوا تو اُن
جانثاروں کا شدید صدمہ کا شکار ہو جانا اس بات کا کیسا واضح ثبوت ہے کہ ان کے وہم و گمان میں بھی کبھی یہ بات
نہ آئی تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کو خدا تعالیٰ کی طرف سے عطا ہونے والی خبروں میں کوئی شک بھی
ہوسکتا ہے اور وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی زبان سے کوئی ناحق بات بھی نکل سکتی
ہے.چنانچہ جب انہیں معلوم ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی کے مطابق یہ تو ثابت نہیں ہوتا
کہ اسی سفر میں وہ حج کریں گے تو کس طرح اُن کے دل تسلی پا گئے.اسی یقین کی دولت پر تو خدا نے صلح حدیبیہ جیسی
نعمت سے نوازا تھا.ار صحابہ کا یہ ایمان دن بدن بڑھ ہی رہا تھا کم نہیں ہورہا تھا اور عمر بھر کے تجربہ کے بعد انہوں
نے یقین میں اور ترقی کی تھی.چنانچہ لکھا ہے:
حضرت خباب بن الارت رضی اللہ عنہ ان خوش نصیبوں میں سے تھے جنہوں نے چھٹے نمبر پر
اسلام قبول کرنے کی سعادت پائی اس لیے سادس الاسلام کہلائے.آپ آہن گری کا کام
کرتے تھے مشرکین مکہ آپ کو سخت تکالیف دیتے حتی کہ آپ کی بھٹی سے کو ئلے نکال کر ان پر
آپ کو لٹا دیتے اور چھاتی پر پتھر رکھ دیتے تا کہ آپ ہل بھی نہ سکیں.آپ نے ایک لمبے عرصہ
تک تکلیفیں اٹھا ئیں.لوہے کی زرہیں پہنا کر آپ کو دھوپ میں ڈال دیا جا تا اور زرہیں دھوپ
میں انگارہ ہو کر آپ کو جھلسا تیں.آپ بے حال ہو جاتے مگر استقامت کا کوہ وقار بنے رہتے.آپ نے ایک دفعہ بتایا کہ مجھے آگ کے انگاروں پر ڈال کر بھی گھسیٹا جاتا پھر میری کمر کی چربی
Page 182
الذكر المحفوظ
166
اور خون سے وہ آگ بجھتی.ان کے حالات کے باوجود جب اسلام کو ترقی ہوئی اور فتوحات کا
دروازہ کھلا تو اس بات پر رویا کرتے تھے کہ خدانخواستہ ہماری تکالیف کا بدلہ کہیں اس دنیا میں ہی
تو نہیں مل گیا.(اسد الغابہ زیر حالات حضرت خباب بن الارت)
پس اس نظر سے بھی دیکھیں کہ مسلمان جو قرآن کریم کو الہی کلام سمجھ کر اس کی خاطر ہر قسم کی قربانیاں دے
رہے تھے، اگر اس میں ذرہ سا بھی رد و بدل ہوتا یا رد و بدل کا ادنی سا شک بھی ہوتا تو وہ ساتھ چھوڑ دیتے.بلکہ
رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے جانی دشمن ہو جاتے کہ جس کی خاطر بظاہر اپنی دنیا بر باد کر لی، ہر ظلم برداشت
کیا، پیاروں کی جدائی قبول کر لی ، بھائی نے بہن کو چھوڑا ، خاوند بیوی سے الگ ہوا ، ماؤں کے بڑھاپے کے
سہارے ان کی آنکھوں کے سامنے مارے گئے، اپنے پیارے انتہائی کسمپرسی کی حالت میں مبتلا ہوئے جائدادیں
تباہ ہوگئیں اور عمروں کے اثاثے ہاتھوں سے نکل گئے ، وہ سب فراڈ تھا!!! وہ جس پر جانیں نچھاور کر رہے تھے
صرف دھو کہ تھا !!! قرآن کریم کے معاملہ میں ادنیٰ سے اختلاف پر تو وہ بھڑک اُٹھتے تو رڈو بدل کی کسی کوشش یا
سازش پر کیوں کرسب کے سب خاموش رہ سکتے تھے؟ پس رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے صحابہ کا آپ پر
اور آپ پر نازل ہونے والے کلام پر غیر متزل ایمان، محبت، عشق اور ان کی فدایت گواہ ہے کہ وہ تمام تر اس
یقین اور ایمان سے گندھے ہوئے تھے کہ قرآن کریم ایک الہی تعلیم ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم اس
کے معتبر ترین محافظ ہیں.صرف یہی نہیں مکی زندگی کے بہیمانہ ظلم وستم سے بھرے ہوئے تیرہ سالوں کے وہ پتے دن اور تاریک
راتیں گواہ ہیں.مدنی دور کی بے چین راتیں اور ہیبت ناک ابتلا شاہد ہیں کہ آنحضور اور آپ کے صحابہ سکتی زندگی
کے ان شب روز میں بھی اس الہی امانت کی تن دہی سے حفاظت کرتے رہے.اگر کوئی تحریف کرنا ہی تھی تو
مشکلات کے اس دور میں اپنی اور اپنے جانثاروں کی حالت زار دیکھ کر نہ کر لیتے ؟ خاص کر جبکہ مخالفین کی طرف
سے یہ کھلا پیغام تھا کہ یہ ظلم ستم بھی ختم ہو جائے گا اور ہم آپ کو سینوں سے لگالیں گے.مال و دولت ، عزت و جاہ
اور سرداری سے نوازیں گے.بس آپ ہمارے معبودوں کے بارہ میں اپنے پر نازل ہونے والے کلام میں سے
سخت الفاظ نکال دیں یا تعریفی کلمات شامل کر دیں.پھر اس حوالہ سے بھی دیکھیں کہ کس طرح ممکن ہے کہ اس شان کا رحیم اور کریم جو انسان تو در کنارکسی بلکتے ہوئے
جانور کو دیکھ کر بھی بے قرار ہو جایا کرتا تھا.تڑپتی اور سکتی ہوئی انسانیت کے دکھوں کا مداوا یعنی کلام الہی اپنے ہاتھوں
سے زیروز بر کردے؟ نیز یہ کہ اس درجہ کا رحیم انسان جس کا وجود جاں دُشمنوں کے لیے بھی دُعا ہی دُعا تھا اگر اس کے
Page 183
قرآن کریم میں تحریف کے الزامات کے جواب
167
سامنے اس کے کسی ایک بھی جانثار کو بھی کوئی ادنی سی تکلیف پہنچائی جائے تو کیسے ممکن ہے کہ وہ برداشت کر لے؟
ایسے جانثار جو مشکلات اور مصائب کی آندھیوں میں بھی یہ نعرے بلند کرتے ہوئے آگے بڑھا کرتے تھے کہ:
” (اے خدا کے رسول ) ہم آپ سے وہ کچھ نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ (علیہ
السلام) سے کہا جاتو اور تیرا رب جا کر ان دشمنوں سے جنگ کرو ہم تو یہیں بیٹھے ہیں.بلکہ ہم
تو آپ کے دائیں بھی لڑیں گے اور بائیں بھی.آپ کے آگے بھی لڑیں گے اور آپ کے پیچھے بھی
اور خدا کی قسم ! دشمن آپ تک نہیں پہنچ سکے گا جب تک ہماری لاشوں کو نہ روند لے.“
(بخاری کتاب المغازى باب اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لهم)
جو یہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں یہ بھی گوارا نہیں کہ ہم اپنے گھروں میں آرام سے ہوں اور محمدصلی اللہ علیہ وسلم
کو راہ چلتے کوئی کانٹا بھی چھ جائے.اگر ردو بدل کرنا ہوتا تو کیا ممکن نہیں تھا کہ ان جانثاروں کی تکالیف دیکھ کر
آپ ان کی مشکلات کم کرنے کے لیے کوئی تبدیلی کر لیتے.Stanley Lane-Poole لکھتا ہے اور کیا خوب
لکھتا ہے:
"He was the most faithful protector of those he protected,
(Stanley Lane-Poole: The Speeches and Table-Talk of the
Prophet Mohammad, Introduction, pp.29.)
یعنی آپ محافظوں میں سب سے زیادہ ایمان دار محافظ تھے.پس کیوں نہ قرآن کریم میں ادنیٰ سے تبدیلی کر کے اپنے جانثاروں کو محفوظ کر لیا؟ اسی لیے نا کہ یہ معتبر محافظ ہی
تو قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری نبھارہا تھا.کوئی تبدیلی ممکن ہی کس طرح تھی ؟
پس صرف صداقت اور امانت ہی دو ایسے اخلاق نہیں کہ جن کی رُو سے آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر
یقین کامل پیدا ہوتا ہے بلکہ من حیث الجمیع آپ انتہائی اعلیٰ اخلاق کے حامل ایک انسان کامل تھے.زندگی کے
ہر شعبہ میں اور اخلاقیات کے ہر میدان میں اتنا بلند اور عظیم نمونہ دکھایا کہ آپ کی سیرت کا مطالعہ کرنے والے
کے دل میں یہ بات اپنی میخ کی طرح کامل طور پر گڑ جاتی ہے کہ اس شان کا انسان جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا.پہلے بھی
ذکر گز را که بیوی تو جلوت و خلوت کی ساتھی اور انسان کی تمام خامیوں اور خوبیوں سے واقف ہوتی ہے.چنانچہ
آپ کے اعلیٰ اخلاق کے بارہ میں ایک بیوی حضرت خدیجہ جو کہ غم والم کے دور کی ساتھی تھیں ، کی گواہی گزر چکی
ہے.ان کی گواہی کے بعد اب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی گواہی بھی دیکھیے جو کہ فاتحانہ زندگی میں آپ کے
ساتھ رہیں.آپ فرماتی ہیں:
من حدثك ان محمدا كتم شيئا مما انزل الله عليه فقد كذب والله
Page 184
الذكر المحفوظ
168
يقول "يَأَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ...الآية
( بخاری کتاب تفسیر القرآن باب يا أيها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك)
یعنی اگر کوئی تم سے کہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی الہی میں سے کوئی آیت چھپا
کر رکھی تھی تو وہ جھوٹا ہے.کیونکہ اللہ تعالی صاف طور پر فرماتا ہے يَأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِغْ مَا
أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ...الاية “ (المائده: 68) یعنی اے رسول جو تیرے رب نے تجھ پر
نازل کیا ہے اسے آگے پہنچا دے.اس روایت سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی بسر
کرنے کے بعد اس نتیجہ پر پہنچی تھیں کہ ناممکن ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم خدا تعالیٰ کی حکم عدولی کریں
اور اس کی طرف سے آنے والی کوئی وحی بنی نوع انسان کے سپرد نہ کریں.پھر حجتہ الوداع کے موقع پر آپ نے تمام موجود صحابہ سے اس امر کی گواہی لی کہ آپ نے الہی امانت کو ان تک
کامل اور مکمل طور پر پہنچا دیا ہے.دُنیا کی کوئی بھی عدالت چند گواہوں پر ہی فیصلہ کر دیتی ہے.پس ان لاکھوں
گواہوں کی گواہی کیوں کر جھٹلا ئی جاسکتی ہے؟ قدم قدم پر ایسی گواہیاں ہیں کہ باقی تاریخ میں کسی بھی بڑے سے
بڑے انسان کو اس شان کی ایک گواہی بھی نصیب نہیں ہوئی جو مثال میں ان گواہیوں سے میل کھائے.پس آپ
کے قریبی عزیز اور اقربا جنہوں نے زندگی کے ہر موڑ پر آپ کے اسوہ کا گہری نظر سے مشاہدہ کیا تھا، آپ کے بارہ
میں کامل طور پر اس ایمان پر قائم تھے کہ آپ بلاشبہ ایک راست باز انسان تھے اور خدا کے سچے نبی تھے جس نے
خدا کے پیغام کو بنی نوع تک پہنچایا اور اس کی حفاظت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی.پھر صحابہ اپنے آقا کے عشق میں فنا ہونے کے باوجود آپ کے کلام اور کلام الہی میں واضح فرق کرتے تھے.چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا عاشق رسول جب کلام الہی کی حفاظت کا سوال آتا ہے تو اپنے محبوب آقا کے
اقوال جلانے کا حکم جاری کر دیتا ہے.یہ واقعہ بھی دوسرے واقعات کی طرح صحابہ کے ایمان کامل کا کیسا اعلیٰ اور
لطیف ثبوت ہے.صحابہ کے عدیم النظیر ایمان کے بارہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں:
صاف ظاہر ہے کہ جو کچھ صحابہ آنحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ایمانی صدق دکھلایا
اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں اور اپنی آبروؤں کو اسلام کی راہوں میں نہایت اخلاص سے
قربان کیا اس کا نمونہ اور صدیوں میں تو کجا خود دوسری صدی کے لوگوں یعنی تابعین میں بھی
نہیں پایا گیا اس کی کیا وجہ تھی ؟ یہی تو تھی کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے اس مرد صادق کا منہ دیکھا
Page 185
قرآن کریم میں تحریف کے الزامات کے جواب
169
تھا جس کے عاشق اللہ ہونے کی گواہی کفار قریش کے منہ سے بھی بے ساختہ نکل گئی اور روز کی
مناجاتوں اور پیار کے سجدوں کو دیکھ کر اور فنا فی الا طاعت کی حالت اور کمال محبت اور
دلدادگی کے منہ پر روشن نشانیاں اور اس پاک منہ پر نور الہی برستا مشاہدہ کر کے کہتے تھے
عشق محمد علی ربہ کہ محمد صلی اللہ علیہ والہ وسلم اپنے رب پر عاشق ہو گیا ہے اور پھر صحابہ
نے صرف وہ صدق اور محبت اور اخلاص ہی نہیں دیکھا بلکہ اس پیار کے مقابل پر جو ہمارے سید
محمد صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے دل سے ایک دریا کی طرح جوش مارتا تھا خدا تعالیٰ کے پیار کو بھی
تائیدات خارق عادت کے رنگ میں مشاہدہ کیا تب ان کو پتہ لگ گیا کہ خدا ہے اور ان کے دل
بول اٹھے کہ وہ خدا اس مرد کے ساتھ ہے.انہوں نے اس قدر عجائبات الہیہ دیکھے اور اس قدر
نشان آسمانی مشاہدہ کئے کہ ان
کو کچھ بھی اس بات میں شک نہ رہا کہ فی الحقیقت ایک اعلیٰ ذات
موجود ہے جس کا نام خدا ہے اور جس کے قبضہ قدرت میں ہر یک امر ہے اور جس کے آگے کوئی
بات بھی انہونی نہیں اسی وجہ سے انہوں نے وہ کام صدق وصفا کے دکھلائے اور وہ جانفشانیاں
کیں کہ انسان
کبھی کر نہیں سکتا.جب تک اس کے تمام شک وشبہ دور نہ ہو جائیں اور انہوں نے
بچشم خود دیکھ لیا کہ وہ ذات پاک اسی میں راضی ہے کہ انسان اسلام میں داخل ہو اور اس کے
رسول کریم کی بدل و جان متابعت اختیار کرے تب اس حق الیقین کے بعد جو کچھ انہوں نے
متابعت دکھلائی اور جو کچھ انہوں نے متابعت کے جوش سے کام کئے اور جس طرح پر اپنی جانوں
کو اپنے برگزیدہ ہادی کے آگے پھینک دیا یہ وہ باتیں ہیں
کہ کبھی ممکن ہی نہیں کہ انسان کو حاصل
ہوسکیں جب تک کہ وہی بہار اس کی نظر کے سامنے نہ ہو جو صحابہ پر آئی تھی.(روحانی خزائن جلد ششم شہادۃ القرآن صفحہ 347,348)
پس ثابت ہوا کہ آپ کا اور آپ کے جانثاروں کا ایمان اس بات کا واضح اور بین ثبوت ہے کہ قرآن کریم
محفوظ ترین ہاتھوں سے ہوتا ہوا ہم تک پہنچا ہے.آپ کی سیرت کے اور بھی بہت سے پہلو اس بات کے ثبوت
میں پیش کیے جاسکتے ہیں کہ قرآن میں کوئی تبدیلی آپ کی ذات سے بعید از قیاس تھی.مگر اس لحاظ سے مطالعہ
مضمون کو بہت ہی طویل کر دے گا.ساری زندگی ایک روشن مینار ہے اور ہر قسم کے شکوک کو رفع کرتی ہے.آنحضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی سیرت کے پہلوؤں کو دیکھ کرکوئی دیانت دار شخص ، دوست یا مخالف، یہ تصور بھی
نہیں کر سکتا کہ آپ جیسے عالی شان اسوہ کا حامل شخص بددیانتی کا بھی مرتکب ہوسکتا ہے.جس نے بھی آپ کی زندگی
کا بلا تعصب، دیانت داری سے مطالعہ کیا وہ آپ کا عاشق بن گیا اور اس ایمان پر قائم ہو گیا کہ آپ بلاشبہ بے عیب
Page 186
الذكر المحفوظ
170
کردار کے مالک انسان ہیں.آپ ہی انسان کامل ہیں.دوستوں اور مخالفوں کی گواہیاں گزر چکی ہیں مگر یہ گواہیاں ایسی نہیں کہ ان کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہو.بلکہ یہ
سلسلہ آج بھی جاری وساری ہے: اپنی بسنٹ رقم طراز ہیں:
It is impossible for anyone who studies the life and
character of the great Prophet of Arabia, who knows
how he taught and how he lived, to feel anything but
reverence for that mighty Prophet, one of the great
messengers of the Supreme.(Annie Besant: The Life and Teachings of Muhammad.Madras
1932, p.4.)
یہ بات ناممکن ہے کہ ایسے شخص کے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث کیے گئے اس عظیم
الشان پیغمبر کے بارہ میں انتہائی ادب اور احترام کے جذبات کے علاوہ کسی قسم کے دوسرے جذبات
پیدا ہوں جس نے اس عظیم المرتبت نبی عربی (صلی اللہ علیہ والہ وسلم) کی سیرت و سوانح کا مطالعہ
بھی کر رکھا ہو اور یہ بھی جانتا ہو کہ آپ نے کس طرح قوم کی تعلیم و تربیت کی اور آداب زندگی
سکھائے اور عملی زندگی کیسے گزاری اور کیسا اسوہ حسنہ پیش کیا.ٹامس کارلائل لکھتا ہے:
During three-and-twenty years of rough actual trial, I
find something of a veritable hero necessary for that
myself.(Thomas Carlyl:On Heroes, Hero-Worship and the Heroic in
History, p.62)
اس کامل انسان کی زندگی کے حقیقتا المناک ابتلاؤں سے بھرے ہوئے 23 سالہ دور حیات
کے مطالعہ سے مجھے اپنی ذات کے لیے ہر قسم کی راہنمائی کا سامان ملتا ہے.There is something so tender and womanly, and with
all so heroic, about the man that one is in peril of finding
the judgment unconsciously blinded by the reeling of
reverence, and well-nigh love, that such a nature
inspires.(John Davenport: An Apology for Mohammad and the Koran,
pp.52, 53)
آپ کی شخصیت ایسی مسحور کن ملاحت اور مردانگی کا مرقع تھی کہ مطالعہ کرنے والے کے دل
میں لاشعوری طور پر انتہائی ادب کے جذبات پیدا ہوتے ہیں اور ایک ایسی شدید محبت میں کھویا
جاتا ہے جو کہ ایک ایسی ہی ہستی سے ہوسکتی ہے.
Page 187
171
قرآن کریم میں تحریف کے الزامات کے جواب
The greatest success of Mohammad's life was effected
by sheer moral force.(Edward Gibbon and Simon Oakley in 'History of the Saracen
Empire,' London, 1870.)
محمد (ﷺ) کی زندگی کی تمام تر عظیم فتوحات میں آپ کے اخلاق عالیہ کا پہلو سب
بڑھ کر کارفرما نظر آتا ہے.مشہور فرینچ شاعر اور مفکر LaMartine نے کیا ہی خوبصورت خراج تحسین پیش کیا ہے:
Philosopher, orator, apostle, legislator, warrior,
conqueror of ideas, restorer of rational dogmas of a cult
without images, the founder of twenty terrestrial
empires and of one spiritual empire, that is Muhammad.As regards all standards by which human greatness may
be measured we may well ask, is there any man greater
than he.(Lamartine: Historie de la Turquie, Pari 1854, vol.2, pp.276-277.)
فلاسفر، دانش ور، رسول مقتن جنگجو، دلوں کو تسخیر کرنے والا ، دین کو منطقی بنیادوں پر استوار
کرنے والا ، ایک بت شکن مذہب کا بانی، ایک روحانی اور میں دُنیاوی سلطنتوں کا بانی.یہ ہیں
محمد (صلی اللہ علیہ وسلم ).ان تمام پیمانوں کی رو سے جن سے کسی بھی انسان کی عظمت کو ماپا
جا سکتا ہے ہم یہ پوچھتے ہیں کہ کیا محمد (ﷺ) سے بڑھ کر بھی کوئی شخص عظیم ہوسکتا ہے؟!!!
بے شمار گواہیاں ہیں اور ہر گواہی درج کرنے کو جی چاہتا ہے مگر یہ تو ایک مکمل جہان ہے اور ایک نا پیدا کنار
سمندر.ہزاروں ہزار صفحات لکھے جاچکے ہیں اور آنحضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرنے کے بعد کسی بھی
دیانت دار غیر متعصب شخص کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ ہے ہی نہیں کہ ان گواہیوں میں اضافہ کیسے بنارہ سکے.اس درجہ کی عظمت کا حامل انسان جو اخلاق عالیہ کے بلند ترین مراتب پر فائز اور اپنے روز مرہ کے معاملات
میں جانی دشمنوں سے بھی اس شان کا اخلاقی رویہ دکھاتا ہے کہ تاریخ کے صفحات ان کی نظیر پیش کرنے سے قاصر
ہیں.کیا گمان کیا جاسکتا ہے کہ جب خدا تعالیٰ کا معاملہ آئے گا تو کسی بددیانتی کا مرتکب ہوگا ؟ کیا ساری معلوم
تاریخ میں کوئی اور کتاب اس درجہ استناد کو پہنچے ہوئے منبع سے نکلی ہے؟ کوئی معیار صداقت تو ہوگا جس کو بنیاد بنا
کر سچ اور جھوٹ میں تمیز کی جاسکے.کوئی معیار تو پیش کرو اور اگر کوئی نہیں تمہارے علم میں، تو یہ معیار صداقت جو
ہم پیش کرتے ہیں، اس کو جھٹلا دو یعنی قانون شہادت یہ صداقت معلوم کرنے کا ایک ایسا معیار ہے جس پر
تمام دُنیا کی تاریخ کی بنیاد ہے.اس کو رڈ کر دینا تمام تواریخ کو رڈ کرنے کے مترادف ہے.خاص طور پر جب
Page 188
الذكر المحفوظ
172
حضرت محمد صلی اللہ علیہ والہ وسلم اس میدان میں قدم رکھیں تو تمام دنیائے تاریخ کی مستند ترین بات ہوتی ہے اس
کی وجہ یہ ہے کہ اور کوئی اس درجہ استناد کو نہیں پہنچا کہ مخالف اور موافق ہر ایک اس کی صداقت کا گواہ بن
جائے.حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں:
افسوس کہ یہ لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کسرشان روار کھ کر یہ خیال نہیں کرتے کہ اس
سے ایک عالم کی کسرشان لازم آتی ہے.کوئی اپنی عقل پر ناز کرے یا بزعم خود کسی دوسرے نبی کا
تابع بن بیٹھے.اس کے لئے یہی سیدھا راستہ ہے کہ اوّل انتہا کی کوشش کر کے قرآن شریف کے
حقائق و معارف کے مقابلہ پر اپنی عقل یا اپنی الہامی کتاب میں سے ویسے ہی حقائق حکیمہ نکال کر
دکھلا دے پھر جو چاہے بکا کرے.مگر قبل اس کے جو اس مہم کو انجام دے سکے جو کچھ وہ کسر شان
قرآن شریف کرتا ہے یا جو الفاظ تحقیرانہ حضرت خاتم الانبیاء کے حق میں بولتا ہے.وہ حقیقت میں
اسی نادان ناقص العقل پر یا اس کے کسی نبی و بزرگ پر وارد ہوتے ہیں.کیونکہ اگر آفتاب کی روشنی
کو تاریکی قرار دیا جائے تو پھر بعد اس کے اور کون سی چیز رہے گی جس کو ہم روشن کہہ سکتے ہیں.براہین احمدیہ حاشیہ نمبر گیارہ روحانی خزائن جلد اول صفحہ 359, 358 یڈیشن اول صفحہ 308 )
پس اس شان کا امین انسان راوی ہو اور مؤمن تو کیا جانی دشمنوں کی گواہی بھی موجود ہو تو اس صورت میں
محقق کے لیے لازم ہو جاتا ہے کہ تسلیم کرے اور رڈ کرنے کی صورت میں تمام دنیا کی مذہبی اور غیر مذہبی تاریخ کو
رڈ کرنا پڑتا ہے کیونکہ تمام مذہبی صحائف میں صرف قرآن ہی ہے جو تاریخ کا حصہ ہے.باقی صحائف قبل از تاریخ
کے زمرہ میں آتے ہیں اور مذہبی تاریخ کے علاوہ دوسری تاریخ بھی اس درجہ استناد کو نہیں پہنچتی.جب بھی تاریخ
کو مانیں گے قرآن کو مانیں گے اور اگر ثابت شدہ تاریخی صداقتوں کو جھٹلانا بھی شروع کریں تو تمام تاریخ کے بعد
قرآن کریم کی سمت نظر کرنا پڑے گی.پھر تاریخی پہلو کے علاوہ بھی بیشمار ایسے پہلو ہیں جن کو رد نہیں کیا جاسکتا.مثلاً تاریخی استناد کو پس پشت بھی
ڈال دیا جائے تو ہر زمانہ میں نازل ہونے والی قرآن کریم کی تاثیرات قدسیہ اس کی صداقت کے ثبوت میں
سامنے آکھڑی ہوتی ہیں.پھر وہ علوم جو قرآن میں بیان ہیں اور انسانی پہنچ سے باہر ہیں اور ایسے ہیں کہ جو صرف خدا
تعالیٰ ہی بتا سکتا ہے، گواہی دیں گے کہ قرآن کریم کلامِ الہی ہے.پھر قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے
کے نتیجہ میں وصال الہی کے مرتبہ کو پانے والے اس کے متبعین قرآن کریم کی صداقت کے گواہ کے طور پر آموجود
ہوں گے جو ہر زمانہ میں اس بات کے ثبوت کے طور پر موجو د رہے ہیں کہ قرآن کریم محفوظ کلام الہی ہے جو آج
بھی اپنے متبعین کو اولین سے ملاتا ہے اور ان میں صحابہ کی خصوصیات پیدا کر دیتا ہے.پس قرآن کریم کی حفاظت
Page 189
قرآن کریم میں تحریف کے الزامات کے جواب
173
پر بے شمار نا قابل تردید دلائل ہیں اور ہر دلیل اپنے کمال کو پہنچی ہوئی ہے.حفاظت قرآن کی خاطر اختیار کیے گئے الہی وسائل پر ایک اجمالی نظر ہم ڈال چکے ہیں.اگر اس تمام تر احتیاط
کے باوجود جھوٹ راہ پا سکتا ہے تو پھر تو بدرجہ اتم ماننا پڑے گا کہ کتاب "Why I Am Not A Muslim" جھوٹ
کا ایک غلیظ پلندہ ہے کیونکہ مصنف بار بار دجل اور فریب سے کام لیتا ہے اور یہ بات بلا مبالغہ کہی جارہی ہے.قاری اس کی مثالیں بار بار دیکھے گا کہ ابن وراق کس طرح دجل اور فریب سے کام لیتا ہے اور اسلامی تاریخ کا
مطالعہ رکھنے والا اگر اس کتاب کے کوئی سے دس صفحات بھی پڑھے گا تو اسے ضرور جھوٹ کی ایک چھوڑ بیسیوں
مثالیں مل جائیں گی.قرآن کریم میں مختلف آیات کے بارہ میں مختلف آراء رکھنے والے محققین اور مفسرین نے ہمیشہ آزادی کے
ساتھ اپنی آراء کا اظہار کیا ہے.مگر آیت إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ.(الحجر: 10) کے بارہ
میں ہر دور کے عظیم مسلمان محققین نے ہمیشہ ایک ہی رائے رکھی ہے اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی
حفاظت کا جو وعدہ کیا ہے وہ پورا کر دکھایا.اسلامی تاریخ میں اعلی علمی مقام کا حامل کوئی ایک بھی ایسا محق نہیں ملتا
جو حفاظت قرآن کے موضوع پر کبھی شک میں مبتلا ہوا ہو.پس کیسے ممکن ہے کہ ہر معمولی سے معمولی بات کو نوٹ
کرنے والے صحابہ اور پھر بعد میں آنے والے محققین کوئی ایسا قرینہ موجود پاتے جو یہ سوچنے پر مجبور کرتا کہ
محمد صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے اپنی طرف سے قرآن کریم میں کوئی رد و بدل کی ہے اور پھر خاموشی اختیار کرتے ؟
خاص طور پر اس صورت میں کہ جب دُنیا کے مختلف حصوں میں آزادانہ تحقیق ہوئی اور ایک دوسرے سے کوئی رابطہ
نہ ہونے کے باوجود تمام نامی گرامی مسلم محققین ایک ہی نتیجہ پر پہنچے.ایک طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا اور آپ کے جانثاروں کا پاک اسوہ ، اور پھر اس پر دیانت داری
سے تحقیق کرنے والے اپنوں اور غیروں کی گواہیاں بھی اور دوسری طرف اس قوم کو دیکھیے جو آپ کی مخالفت
پر کمر بستہ تھی.جہاں وہ رسول کریم کے صداقت اور امانت و دیانت اور دوسرے اخلاق عالیہ پر فائز ہونے کا
اقرار کرتے رہتے تھے وہاں کبھی کبھی دبے لفظوں میں آنحضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے بالمقامل اپنے دجل اور
فریب کا اقرار بھی کرتے تھے.ابوسفیان کا اقرار درج ہو چکا ہے.پھر اسلام سے قبل کا اور اسلام کے نزول کے
دور کا ادب جاہلی عربوں کی زبان سے ان کی اخلاقی زبوں حالی کی داستان ہے جس کی تصدیق ہر مؤرخ نے کی
ہے.یہی حال آج کے مخالفین اسلام کا ہے.بہت سے مغربی محققین نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ اُن کی
قوم تحقیق کے نام پر اسلام کے خلاف شرمناک بددیانتی اور جھوٹ کی مرتکب ہوئی ہے.پس جب مخالف خود
اپنے جھوٹے ہونے کا اقرار کر رہا ہو اور اپنی اخلاقی پستی کا گواہ ہو اور ساتھ ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
Page 190
الذكر المحفوظ
174
کے اخلاق عالیہ کا مداح ہو اور آپ کے سچا ہونے پر دل و جان سے متفق ہو تو پھر آج کے متعصب سے متن
انسان کے پاس بھی اس کے سوا اور کیا چارہ ہو سکتا ہے کہ تسلیم کر لے اور تعصب کسی اور جگہ نکالے.اگر تسلیم نہیں
کرنا تو پھر ایک ہی حل ہے کہ ابن وراق کے پاس چلا جائے.دُنیا سے چھپ جائے.آخر بد باطن کو دُنیا کا ہی ڈر
تو ہوتا ہی ہے لیکن کیا ہی بدنصیبی ہے کہ دنیا کے لیے جھوٹ سے لیٹے تو پھر دنیا سے ہی چھپنا پڑا.پس ابن وراق
کا یہ کہنا کہ شیطانی آیات کے واقعہ سے معلوم ہوتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے
نعوذ باللہ کوئی بددیانتی کی تھی ، غلط بات ہے.در حقیقت یہ واقعہ تو کفار مکہ کی بددیانتی کا ثبوت ہے.رسول کریم
کی حیات مطہرہ کا مطالعہ کرنے والا انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ ﷺ نے
نعوذ باللہ کوئی غلط بات کی.یہ تو کسی بد بخت مخالف کی بددیانتی تھی جس نے موقع کا فائدہ اُٹھا کر یہ حرکت
کر دی.اگر ( نعوذ باللہ ) رسول کریم کا مقصد کفار کو خوش کرنا ہی ہوتا تو کسی ایسے موقع پر کرتے جب ضرورت
تھی.مثلاً جب وہ حضرت ابو طالب کے پاس شکوہ لے کر آئے اور کسی بڑے رد و بدل کا مطالبہ نہ کیا بلکہ صرف
یہ کہا کہ ہمارے بتوں کو بُرا بھلا نہ کہو اور جن آیات میں بتوں کی مذمت ہے انہیں نکال دو.ہم اسی میں خوش
ہو جائیں گے اور تمہیں انعام و اکرام سے بھی اور آئندہ کے لیے ترقی کے دروازے بھی کھول دیں گے.عزت و وجاہت سے بھی نوازیں گے تو آپ ان کی بات مان لیتے.جب شعب ابی طالب میں محصور تھے اس
وقت کوئی رد و بدل کرتے.جب طائف میں لہولہان ہوئے اس وقت کوئی رد و بدل کرتے.جب جانثاروں
پر ظلم وستم ہورہا تھا اس وقت کوئی رد و بدل کرتے.جب گنے چنے جانثار شہید ہورہے تھے اس وقت خوش
کرنے کی کوشش کرتے.یہ کیا کہ بیٹھے بیٹھے نہ کوئی مطالبہ ہوا اور نہ ہی کوئی ظلم اور یک دم رد و بدل کر دیا.پس اصل بات تو وہی ہے جو امام الزماں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الفاظ میں گزر چکی کہ ” پس یہی تو
سیاہ باطنی کی نشانی ہے اور اسی سے تو ان کی اندرونی خرابی مترشح ہورہی ہے انبیاء وہ لوگ ہیں کہ
جنہوں نے اپنی کامل راستبازی کی قومی حجت پیش کر کے اپنے دشمنوں کو بھی الزام دیا ، پس شیطانی
آیات کے واقعہ سے اس بارا بن وراق کی ہی سیاہ باطنی اور اندرونی خرابی مترشح ہورہی ہے.رسول کریم ﷺ کو قرآن کریم میں کسی رد و بدل کا موقع میسر نہیں تھا
صلى
الله
اسی بحث کے اس ایک پہلو پر تو ہم نے بات کی کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق فاضلہ کے اس مقام پر فائز
تھے کہ آپ کی ذات سے کسی قسم کی بددیانتی کا تصور بھی محال ہے.دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کے اخلاق
فاضلہ اور مقام عالیہ کو اپنے تعصب اور اندھے پن کی وجہ سے دیکھنے سے انکار کرتا ہے تو بھی اس کے لیے قرآن کریم
Page 191
قرآن کریم میں تحریف کے الزامات کے جواب
175
کو محفوظ ماننے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جب کوئی وحی الہی ایک بارڈ نیا
کے سامنے پیش کر دیتے تھے تو پھر اُس میں کوئی رد و بدل محال ہو جاتا تھا.اس کی وجوہات جمع القرآن کی تاریخ
کی بحث میں گزر چکی ہیں.ذیل میں ہم مختصر طور پر نمبر وار درج کر دیتے ہیں کہ کیوں رد و بدل محال تھا.1- قرآن کریم کے نزول کے ساتھ ہی آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے تحریری شکل میں محفوظ کر وا دیتے اور پھر
ان
مستند تحریرات سے صحابہ کثرت سے اپنے لیے نقول تیار کر لیتے.پس کسی بھی تبدیلی کی صورت میں اتنے نسخوں
میں تبدیلی کروانی ہوتی جو کہ ناممکن بھی تھی اور تاریخ میں ایک بھی ایساذ کر نہیں ملتا کہ کبھی آپ نے ایسا کرنے کی
کوشش بھی کی ہو.2- تحریر کے ساتھ ہی آپ چنیدہ صحابہ کو وحی الہی حفظ کروا دیتے اور ان کے حفظ کی درستگی کا یقین کر لینے کے
بعد ان کا فرض ہوتا کہ وہ کثرت سے دیگر صحابہ کو حفظ کروا دیں.اس طرح نزول کے معا بعد حفظ کے ذریعے کلام
الہی بہت سے سینوں میں محفوظ ہو چکا ہوتا.3.پھر صرف حفاظ ہی حفاظت قرآن کے محافظ نہیں تھے بلکہ نماز میں بھی تلاوت قرآن فرض تھی اس لیے ہر
مسلمان
کو کچھ نہ کچھ حصہ یاد کرنا ہوتا تھا جو نماز میں لوگوں کے سامنے تلاوت کیا جاتا.پھر ہر رمضان میں اس کی
دہرائی ہوتی.4.پھر جن لوگوں کے سپرد یہ امانت ہوئی تھی یعنی آنحضور کے صحابہ، اُنکا نمونہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ وہ
ایمان کے کس اعلیٰ مقام پر فائز تھے کہ مطالعہ کرنے والے کو یقین ہو جاتا ہے کہ وہ لازماً قرآن کریم کو الہی کلام
سمجھتے تھے اور اس بات پر یقین ہو جاتا ہے کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ان لوگوں میں سے کوئی ایک بھی ایسا ہو جو قرآن کریم
کے معاملہ میں ذرہ سی بھی بددیانتی کی ادنی سی بھی کوشش پر خاموشی اختیار کرسکتا ہو اور نہ ہی تاریخ میں کوئی ایسی
مثال ملتی ہے.بلکہ جہاں ادنی سی بھی غلط فہمی پیدا ہوئی تو بپھرے ہوئے شیروں کی طرح کھڑے ہو گئے.جب
انفرادی طور پر یہ حالت ہے تو کیسے یہ ممکن ہے کہ کوئی بد دیانتی ہوئی ہو اور اس پر ساری قوم نے خاموشی اختیار کی
ہو؟ یہ تو قومی بددیانتی بن جاتی ہے اور کسی بھی قوم کا اس طرح خاموشی سے
کسی قومی بددیانتی پر متفق ہو جانا کہ کسی کو
کانوں کان
خبر نہ ہو، ہرگز ممکن نہیں.تاریخ ایسی کوئی مثال پیش نہیں کر سکتی.ایسی بددیانتی کی مرتکب تو وہ قوم اس
وقت بھی نہ ہوسکی جب کہ اخلاقی، ذہنی، روحانی اور دنیاوی لحاظ سے انتہائی درجہ کی پستی میں گری ہوئی تھی ، جب
پہلے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے اپنی سچائی پر اس قوم سے قو می گواہی طلب کی ، تو اب کیونکر ممکن تھا
کہ اخلاقی ، روحانی اور دنیاوی آداب کے نئے اور اعلیٰ پیمانے قائم کرنے والی قوم اس قومی بددیانتی کی مرتکب
ہو جاتی؟ صحابہ کی وفاداری اور جانثاری کا اندازہ ان کے حالات سے ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے پیغام الہی کی
Page 192
الذكر المحفوظ
176
حفاظت کے لیے ایسے اعلیٰ نمونے دکھائے کہ تاریخ ان سے پہلے ان نمونوں کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے.انہوں نے ایسے ایسے ہولناک مظالم برداشت کیے کہ پڑھ کر ہی انسان کی روح تک میں لرزہ طاری ہو جاتا ہے.5- کثرت اشاعت کی وجہ سے اپنے اور بیگانے سب گواہ بن جاتے تھے.اس لیے کسی بھی تبدیلی کی صورت
میں مخالفین شور مچادیتے.6- ناصرف یہ کہ مخالفین شور مچا دیتے بلکہ آپ پر ایمان لانے والے صحا بہ بھی فوری طور پر آپ کے مخالف
ہو جاتے کیونکہ وہ آپ پر اسی لیے تو ایمان لائے تھے کہ آپ خدا تعالیٰ کے سچے نبی ہیں.صلح حدیبیہ کی مثال گزر
چکی ہے کہ ادنی سی غلط فہمی ہوئی اور کس طرح صحابہ بے چین ہو گئے.حضرت
مسیح پاک علیہ السلام کے مبارک الفاظ سے اس موضوع کو ختم کر کے آگے بڑھتے ہیں:
لازم ہے کہ جو شخص اپنے تئیں منصف سمجھتا ہے اب وہ اپنا انصاف دکھاوے اور جو اپنے
تیں حق کا طالب جانتا ہے اب وہ حق کے قبول کرنے میں توقف نہ کرے ہاں نفسانی آدمی کو
ایسی صداقت کا قبول کرنا جس کے ماننے سے اس کی شیخی میں فرق آتا ہے ایک مشکل امر ہو گا مگر
اے ایسی طبیعت کے آدمی !! تو بھی اس قادر مطلق سے خوف کر جس سے آخر کار تیرا معاملہ ہے
اور دل میں خوب سوچ لے کہ جو شخص حق کو پا کر پھر بھی طریقہ ناحق کو نہیں چھوڑتا اور مخالف پرضد
کرتا ہے اور خدا کے پاک نبیوں کے نفوس قدسیہ کو اپنے نفس امارہ پر قیاس کر کے دنیا کے لالچوں
سے آلودہ سمجھتا ہے حالانکہ کلام الہی کے مقابلہ پر آپ ہی جھوٹا اور ذلیل اور رسوا ہورہا ہے ایسے
شخص کی شقاوت اور بدبختی پر خود اس کی روح گواہ ہو جاتی ہے کہ جو اس کو ہر وقت ملزم کرتی رہتی
ہے اور بلاشبہ وہ خدا کے حضور میں اپنی بے ایمانی کا پاداش پائے گا کیونکہ جوشخص نہایت سخت اور
جلانے والی دھوپ میں کھڑا ہے وہ ظل ظلیل کا آرام نہیں پاسکتا.“
(براہین احمدیہ چہار حصص روحانی خزائن جلد اول صفحہ 353,354 ایڈیشن اول صفحہ 304 )
Page 193
قرآن کریم میں تحریف کے الزامات کے جواب
177
ترتیب قرآن کریم
قرآن کریم کوئی عام کتاب نہیں بلکہ الہی کلام ہونے کی وجہ سے عام کتب سے منفر داور ممتاز حیثیت کی حامل
ہے لہذا قرآنی فرمودات کی ترتیب اور اس کے اسلوب کا بھی اپنا دستور ہے جو عام کتب کے دستور بیان سے
مختلف اور فی ذاتہ منفرد اور ممتاز ہے.ترتیب قرآن کریم کے موضوع کے دو بنیادی پہلو ہیں.اول : قرآن کریم کی آیات اور سورتوں کی ظاہری ترتیب کا تاریخی پہلو
دوم : قرآن کریم کی معنوی ترتیب اور اس کا اسلوب بیان
معترضین بھی عام طور پر دو قسم کے اعتراضات کرتے ہیں.ایک قرآن کریم کی ظاہری ترتیب پر اور دوسرا
اس کی ترتیب مضامین اور اسلوب بیان پر.جبکہ اہل فکر جن میں مسلمان بھی شامل ہیں اور غیر مسلم بھی ، قرآن کریم
کی معنوی ترتیب اور اس کے اسلوب بیان پر غور وفکر کرتے ہیں.قرآن کریم ظاہری طور پر آیات (Verses)، رکوع ( Ruku)، سورتوں (Chapters) اور
اجزا (Parts) میں منقسم ہے.اس تقسیم میں آیات اور سورتوں کی ترتیب الہی راہنمائی اور منشاء کے مطابق
حضرت محمد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگرانی میں لگوائی تھی جس میں تاحال
کوئی تبدیلی نہیں ہوئی.آیات اور سورتوں کی ظاہری ترتیب کے لحاظ سے بھی قرآن کریم تمام دُنیا کی کتب میں ایک ممتاز اور الگ
مقام رکھتا ہے.ترتیب کے حوالہ سے ایک حقیقت بہت غیر معمولی ہے کہ قرآن کریم کی موجودہ ترتیب وہ ترتیب
نہیں ہے جس میں یہ نازل ہوا تھا بلکہ وہ ترتیب محض اُس دور کے مطابق تھی جس دور میں قرآن کریم نازل ہو رہا
تھا.نزول کے ساتھ ساتھ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کی راہنمائی میں اس کو اس دائگی ترتیب میں مرتب
کرواتے رہے جو کہ آئندہ زمانے کے لیے مناسب اور ضروری تھی اور جو آج رائج ہے.اس ترتیب میں آیات
کی ترتیب بھی شامل ہے اور سورتوں کی ترتیب بھی.قرآن کریم اس حقیقت کو ان الفاظ میں بیان کرتا ہے:
إِنَّ عَلَيْنَا جَمُعَهُ وَ قُرْآنَهُ (القيامة : 18)
یعنی اس قرآن کا جمع کرنا اور اس کی تلاوت ہماری ذمہ داری ہے.ترتیب آیات
جہاں تک آیات کی ترتیب
کا تعلق ہے تو تمام مسلمان متفقین اس بات پر متفق ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نے آیات کی ترتیب اپنی نگرانی میں خود مقر فرمائی تھی نیز یہ کہ اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ قرآن مجید کی ترتیب
Page 194
الذكر المحفوظ
178
جمع کا کام بھی یقینا وحی الہی کے مطابق اور خدا تعالیٰ کی دائمی حکمتوں اور منشا کے تحت ہوا ہے اور ہر وحی کے ساتھ جبریل
علیہ السلام آنحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم کو اس بات سے بھی آگاہ فرماتے تھے کہ اس حصہ وحی کو کس سورت میں کس
جگہ لکھا جائے اور آپ اسی ترتیب کے مطابق اپنے سامنے کا تہوں سے
لکھواتے تھے.چنانچہ روایت ہے کہ:
كان النبي ﷺ لما تنزل الأيات فيدعو بعض من كان يكتب له و يقول
له ضع هذه الآية في سورة التي يذكر فيها كذا و كذا
(سنن ابی داؤد کتاب الصلواة باب من جهر بها)
یعنی جب کوئی آیات نازل ہوتیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم ان ( کاتبین وحی ) میں
سے کسی کو بلا بھیجتے جو آپ کے زیر نگرانی وحی الہی تحریر کیا کرتے تھے اور انہیں ہدایات دیتے کہ
اس آیت کو فلاں سورۃ میں فلاں جگہ رکھ دو.اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس نے حضرت عثمان کا یہ قول روایت کیا ہے:
بسا اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم پر بیک وقت مختلف سورتوں کے حصے نازل
ہوتے تھے.جب بھی کوئی وحی قرآن نازل ہوتی تو آپ کسی لکھنے والے کو جو آپ کے سامنے
بیٹھ کر لکھتا تھا بلا کر فرماتے کہ اس حصہ کو فلاں سورت میں اس جگہ شامل کر کے لکھو جہاں فلاں
فلاں مضمون بیان ہوا ہے اور اس آیت کو فلاں آیت کے ساتھ لکھو.(مسند احمد بن حنبل جلد 2 صفحه 75 حديث عثمان
بن عفان)
پس ترتیب آیات کے بارہ میں مسلمانوں کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ آیات کی موجودہ ترتیب خدا تعالیٰ کی مقرر
کردہ ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق آیات کو مختلف سورتوں میں ان کی جگہوں پر
رکھتے تھے.مستشرقین یہ تو نہیں مانتے کہ قرآن کریم خدا تعالیٰ کا کلام ہے اس لیے ترتیب آیات کے بارہ میں یہ
نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ کی مقرر فرمودہ ہے.ان کا موقف یہ ہے کہ آیات کی یہ ترتیب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کی لگائی ہوئی ہے.ترتیب سور
اکثر مسلمان علما یہ یقین رکھتے ہیں کہ سورتوں کی ترتیب بھی توقیفی یعنی اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ ہے.مگر بعض
کے نزدیک اس بات کے کافی شواہد نہیں ملتے کہ تمام سورتوں کی ترتیب خدا تعالیٰ کی مقرر کردہ ہے بلکہ ان کا خیال
ہے کہ آنحضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے بعض سورتوں کی ترتیب خود مقرر فرمائی تھی اور باقی سورتوں کو امت کی
صوابدید پر چھوڑا تھا کہ جیسے چاہیں مرتب کر دیں.مستشرقین بھی اکثر یہی موقف اختیار کرتے ہیں کہ سورتوں کی
Page 195
قرآن کریم میں تحریف کے الزامات کے جواب
179
ترتیب صحابہ کی لگائی ہوئی ہے اور یہ کہ دائی ترتیب میں جمع کرتے ہوئے ترتیب نزولی کا خیال نہیں رکھا گیا.ابن وراق نے اس معاملہ میں بھی ہرزہ سرائی کی ہے.کہتا ہے:
The Koran is written in Arabic and divided into
chapters (suras or surah) and verses (ayah; plural, ayat).There are said to be approximately 80,000 words, and
between 6,200 and 6,240 verses, and 114 suras in the
Koran.Each sura, except the ninth and the Fatihah (the
first sura) begins with the words "In the name of the
Merciful, the Compassionate." Whoever was responsible
for the compilation of the Koran put the longer suras
first, regardless of their chronology, that is to say,
regardless of the order in which they were putatively
revealed to Muhammad.(Ibn Warraq: Why I am Not A Muslim, Prometheus Books, New
York, 1995, under heading; The Koran: Pg (105)
یعنی قرآن عربی زبان میں لکھا ہوا ہے اور مختلف سورتوں اور آیات میں تقسیم کیا گیا ہے.کہا جاتا
ہے کہ تقریباً 80000 الفاظ ، 6200 سے 6240 تک آیات ہیں.نویں سورت اور الفاتحہ کے
علاوہ جو کہ پہلی سورت ہے، تمام سورتیں ان الفاظ سے شروع ہوتی ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم
جس نے بھی قرآن مدون کیا ہے اس نے زیادہ لمبی سورتیں شروع میں رکھی ہیں بلاتر تیپ نزول یعنی
اس ترتیب کا خیال نہیں رکھا گیا جس میں کہ سمجھا جاتا ہے کہ قرآن محمد (ﷺ ) پر نازل کیا گیا.یہ کہنا کہ " 6200 سے 6240 تک آیات ہیں.اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ گویا آیات میں کسی قسم کی کمی بیشی کا
شبہ ہے یعنی کچھ نسخوں میں کچھ آیات کم ہیں اور کچھ میں کچھ آیات زیادہ ہیں.جیسا کہ ابن وراق نے اعتراض بھی
کیا ہے.دراصل ایسا بالکل نہیں ہے.آیات کے شمار میں اکاڈ کا فرق محض اس لیے ہے کہ بعض علما کے نزدیک
ایک جگہ آیت ختم ہوتی ہے اور بعض اگلی آیت کو بھی گزشتہ آیت کا ہی حصہ سمجھتے ہیں اس طرح شمار کا اختلاف پیدا
ہو جاتا ہے مگر اس سے یہ مراد نہیں کہ الفاظ یا حروف کم یا زیادہ ہیں.اگر بنظر غور دیکھا جائے تو یہ فرق بھی معنوی وسعت کا
باعث ہے.پھر آیات کے شمار کے فرق کی ایک وجہ یہ ہے کہ بعض علما بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ کو ہر
سورت کی پہلی آیت شمار نہیں کرتے اس لیے ان کے شمار میں ہر سورت کی ایک آیت اُن لوگوں کے شمار سے کم
ہوتی ہے جو بسم اللہ کو ہر سورت کی پہلی آیت شمار کرتے ہیں اور اس طرح سارے قرآن کریم میں 113 تک
آیات کے شمار کا فرق پیدا ہو جاتا ہے مگر یہ صرف آیات کے نمبروں کے اندراج اور شمار کا اختلاف ہے.عالم اسلام میں شائع ہونے والے قرآن کریم کے تمام نسخہ جات میں بہر حال ہر سورت سے قبل بسم الله
الرَّحْمنِ الرَّحِيم درج کی جاتی ہے جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی.خواہ اسے سورت کی پہلی
Page 196
الذكر المحفوظ
180
آیت شمار کیا جائے یا نہ کیا جائے.جماعت احمد یہ عالمگیر کی طرف سے شائع ہونے والے نسخہ ہائے قرآن کریم
میں بسم اللہ شمار کر کے آیات کی تعداد 6347 اور رکوع کی تعداد 564 ہے.پس یہ ایسا کوئی اختلاف نہیں کہ اس
سے قرآن کریم کی حفاظت کے معاملہ میں شبہ پیدا ہو.جارج سیل لکھتا ہے:
Having mentioned the different editions of the Koran,
it may not be amiss here to acquaint the reader, that
there are seven principal editions, if I may so call them,
or ancient copies of that book......Of these editions, the
first of Medina makes the whole number of the verses
6,000; the second and fifth, 6,214; the third, 6,219; the
fourth, 6,226; and the last, 6,225.But they are all said to
contain the same number of words, namely, 77,639; and
the same number of letters, vis., 323,015
(George Sale: The Koran; The Preliminary Discourse; Section
3; pg: 45,46)
یہ کہنا کہ قرآن کریم کے مختلف متن ہیں ان سے کہیں قاری غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے کہ گویا
سات مختلف بڑے متن ہیں.اگر میں یہ الفاظ استعمال کروں کہ سات قدیم نسخہ جات ہیں (تو
درست ہوگا ) ان میں سے پہلا جو مدینہ میں تھا اس کی آیات کا شمار 6,000؛ دوسرے اور
پانچویں کی آیات کا شمار 6,614 تیسرے کی آیات کا شمار 6,619 چوتھے کی آیات کا شمار 6,226
اور آخری یعنی چھٹے کی آیات کا شمار 6,225 ہے.مگر یہ کہا جاتا ہے کہ ان سب کے الفاظ کی تعداد
ایک ہی ہے یعنی 77,639 اور یہاں تک کہ حروف کی تعداد بھی ایک ہی ہے یعنی 323,015.اس وضاحت کی ضرورت اس لیے تھی کہ یہاں سے ابنِ وراق اپنے اس دجل کی بنیاد بنارہا ہے کہ قرآن کریم
کے بہت سے متن تھے جو ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے تھے.آئندہ بھی حقائق کو الفاظ کے جامے میں اس
طرح لیٹے گا کہ قاری نامہ نبی کا شکار ہوتا چلا جائے.اسی طرح ابن وراق کی یہ بات بھی درست نہیں کہ سوائے نویں سورۃ اور الفاتحہ کے جو کہ پہلی ہے تمام سورتیں
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیم “ کے الفاظ سے شروع ہوتی ہیں.سورۃ الفاتحہ بھی بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ
الرَّحِیم “ سے ہی شروع ہوتی ہے.ایک مرتبہ پھرا ابن وراق حفاظت قرآن کریم پر حملہ کرتے ہوئے یہ تاثر دینے کی کوشش میں ہے کہ اگر واقعی
قرآن خدا کی طرف سے نازل ہوا بھی تھا تو بھی اب موجودہ قرآن وہ نازل شدہ قرآن نہیں ہے کیونکہ علاوہ
دوسری تبدیلیوں کے، اس کی اصل ترتیب یعنی ترتیب نزولی بھی بدل دی گئی ہے.کہتا ہے : ” جس کسی نے بھی
قرآن مدون کیا ہے اس نے زیادہ لمبی سورتیں شروع میں رکھی ہیں بلا تر تیب نزول..ابن وراق جس کسی نے
Page 197
قرآن کریم میں تحریف کے الزامات کے جواب
181
بھی قرآن مدون کیا ہے“ کے الفاظ سے یہ تاثر دینے کی کوشش بھی کر رہا ہے کہ موجودہ ترتیب کے بارہ میں بھی
شک ہے کہ کس نے لگائی.چنانچہ جب معلوم ہی نہیں کہ کس نے قرآن مدون کیا نیز جب اصل ترتیب ہی بدل دی گئی
تو کس طرح قرآن کریم کو محفوظ کلام الہی مانا جائے؟
ذیل کی سطور میں ہم یہ اس حقیقت کے ثبوت پیش کریں گے کہ سورتوں کی ترتیب بھی خدا تعالیٰ کی مقرر شدہ
ہے اور رسول کریم نے الہی راہنمائی میں اپنی نگرانی میں لگوائی تھی.آنحضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم سورتوں کو نزول
کے ساتھ ہی ایک خاص ترتیب سے لکھواتے اور حفظ کروا دیتے تھے اور قرآن کریم آج بھی بعینہ اُسی ترتیب کے
کروادیتے
ساتھ محفوظ ہے جیسا کہ آنحضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے دور میں تھا.اس حقیقت کے ثبوت میں قرآن کریم کی اندرونی گواہی بھی موجود ہے کہ سورتوں کی ترتیب خدا کی مقرر کردہ
ہے اور بہت سے تاریخی دلائل بھی موجود ہیں.چنانچہ ذیل میں دونوں قسم کے ثبوت درج کیے جاتے ہیں :.سورتوں کی ترتیب پر قرآن کریم کی اندرونی گواہی
سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں یہ دعویٰ فرماتا ہے کہ قرآن کریم کی جمع اور اشاعت کے تمام تر
مراحل خدا تعالیٰ کے ذمہ ہیں.چنانچہ فرماتا ہے : رَتَّلُنهُ تَرْتِيلاً.(الفرقان : 33 ) یعنی ہم نے اس قرآن کی
ترتیب بھی نہایت اعلیٰ درجہ کی رکھی ہے.تمام عربی لغات ترتیل کے معنوں میں تالیف یعنی ترتیب سے جمع کرنے
کے معنے بھی بیان کرتی ہیں.لسان العرب میں ہے رتل الکلام: احسن تالیفہ یعنی کلام کی تالیف کو بہترین
بنایا.پھر فرمایا:
إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَ قُرْآنَهُ (القيامة : 18)
یعنی اس قرآن کا جمع کرنا اور اس کی تلاوت ہماری ذمہ داری ہے.پس کیسے ممکن ہے کہ اتنے واضح ارشادات کی موجودگی میں یہ کہ دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ تو ایک اور ترتیب سے
سے قرآن کریم نازل فرماتا تھا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم اپنی مرضی سے سورتوں کی ترتیب بدل دیتے
تھے اور اُس ترتیب سے نہیں رکھتے تھے جس میں وہ نازل ہو رہی تھیں جبکہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ جمع قرآن
اللہ کی
مرضی سے ہوتا تھا پس جو بھی ترتیب اللہ تعالیٰ لگاتا تھا یہ محال تھا آنحضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم اسے بدلتے.اللہ
تعالیٰ اس وسوسہ کو ر ڈ کرتے ہوئے ایک دوسری جگہ فرماتا ہے:
قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا اثْتِ بِقُرْآن غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلُهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي
أَنْ أُبَدِلَهُ مِنْ تِلْقَايُّ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ
Page 198
الذكر المحفوظ
182
عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (يونس: 16)
ترجمہ: وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی توقع نہیں رکھتے کہتے ہیں اس کی بجائے کوئی اور قرآن
لے آیا اسے ہی تبدیل کر دے.تو کہہ دے کہ مجھے اختیار نہیں کہ میں اسے اپنی طرف سے بدل
دوں.میں نہیں پیروی کرتا مگر اسی کی جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے.اگر میں اپنے رب کی
نافرمانی کروں تو میں تو یا ایک عظیم دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں.حضرت خلیفہ اسیح الثانی رضی اللہ عنہ مذکورہ بالا آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں:
مطلب یہ ہے کہ میں قرآن مجید کے متعلق تمام باتیں وحی الہی سے کرتا ہوں اور اس میں
خود کوئی دخل نہیں دیتا.لہذا میں کوئی تبدیلی یا تغیر نہیں کر سکتا.اس آیت سے ان لوگوں کا بھی
رڈ ہو جاتا ہے جو کہتے ہیں کہ بسمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم کا ہر سورۃ سے پہلے لکھنا
آنحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے حکم سے ہے نہ کہ وحی سے.یا ترتیب قرآن اور سورتوں
کے نام آنحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے خود رکھے ہیں.کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کی طرف سے
فرماتا ہے کہ قرآن مجید سے متعلق میں ہر بات کو وحی سے ہی طے کرتا ہوں اور یہ کہنا کہ بے شک
رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم تو وحی الہی سے ایسا کرتے تھے مگر صحابہ نے اپنی مرضی سے
بعض تغیرات کر دیے.بالکل ہی خلاف عقل ہے.کیونکہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو
حق نہیں تھا تو صحابہ کو کیسے یہ حق حاصل ہوسکتا تھا اور وہ سوائے اس کے کہ نعوذ باللہ انہیں مرتد
قرار دیا جائے کب ایسا کر سکتے تھے؟
( تفسیر کبیر جلد 3 صفحہ 45)
حضرت امام رازگی اس آیت کی تفسیر کے تحت یہ بیان فرماتے ہیں:
سورۃ یونس کی اس آیت کے تحت کئی مفسرین نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ قرآن مجید کی
ترتیب خود خدا تعالیٰ نے قائم تھی اور اپنے رسول کو اس بات
کا کوئی اختیار نہیں دیا تھا کہ اپنی مرضی
سے ترتیب قرآن میں کوئی تصرف کرتے.( تفسیر کبیر رازی جزو 17 صفحہ 55 56 ناشر دارالکتب العلمیہ تہران طبع دوم )
تفسیر القرطبی میں اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے.یہ آیت اس بارہ میں ہے کہ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا کہ
قرآن کو کسی اور ترتیب سے پیش کریں مگر آپ کو اس کا اختیار نہ تھا.اور یہ بات بھی مد نظر
رہے کہ جو کچھ بھی آپ فرماتے تھے جب کہ وہ وحی پر مبنی تھا تو وہ خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوانہ
Page 199
قرآن کریم میں تحریف کے الزامات کے جواب
183
کہ آپ کی طرف سے.( محمد بن عبدالله القرطبي : الجامع لاحكام القرآن القرطبي) جزو 8 ص (319
اور تفسیر القاسمی میں اس آیت کے تحت لکھا ہے:
کفار نے آنحضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ اس قرآن کو کسی اور ترتیب سے یا
کسی اور شکل میں پیش کریں.اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ جواب سکھایا کہ قُلُ مَا يَكُونُ
لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِی یعنی یہ میرے اختیار میں نہیں.میں تو اللہ تعالیٰ کی کہی ہوئی
بات پہنچانے پر مامور ہوں.(محاسن التاويل- تفسير القاسمی جلد 6صفحه 14 از محمد جمال الدین)
پھر قرآن کریم میں نزول کے وقت بھی موجودہ ترتیب کی طرف واضح اشارے کرتا نظر آتا ہے.مثلاً ایک
اندرونی گواہی یہ بھی ملتی ہے کہ جب ایک ایسا شخص قرآن کریم پڑھتا ہے جو اسے خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں مانتا
تو علاوہ دیگر دلائل کے اللہ تعالیٰ ایک چیلنج یہ دیتا ہے:
وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّنْ مِّثْلِهِ وَادْعُوا
شُهَدَاءَ كُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا
فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَفِرِينَ -
(البقرة:2524)
ترجمہ: اور اگر تم اس بارے میں شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا ہے تو اس جیسی
کوئی سُورت تو لا کے دکھاؤ، اور اپنے سر پرستوں کو بھی بلا لاؤ جو اللہ کے سوا بنارکھے ہیں، اگر تم
بچے ہو.پس اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہر گز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان
اور پتھر ہیں.وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے.اب سب سے پہلے یہ پینج سورۃ البقرہ میں دیا گیا ہے اور ایک سورت کی مثال لانے کو کہا گیا ہے.موجودہ
ترتیب میں سورۃ البقرۃ سے پہلے صرف ایک ہی سورت ہے.جو شخص قرآن کریم کو کلام الہی نہیں مانتا، اللہ تعالیٰ
اسے یہ چیلنج دے رہا ہے کہ اگر یہ کلام انسانی ہے تو پھر سورۃ الفاتحہ جیسی ایک سورت تم بھی بنا کر لے آؤ.پھر یہ چیلنج
دوبارہ سورۃ ھود آیت 14 میں دیا گیا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے:
یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے افترا کر لیا ہے.تو کہہ دے کہ پھر اس جیسی دس افترا کی ہوئی
سور میں تولا ؤ اور اللہ کے سوا جسے پکار سکتے ہو ( مدد کے لئے ) پکا روا گرتم سچے ہو.
Page 200
الذكر المحفوظ
184
اب یہاں
اللہ تعالیٰ دس سورتیں بنانے کا چیلنج دیتا ہے.موجودہ ترتیب میں سورۃ ھود گیارھویں سورت ہے.گویا جس نے یہ چیلنج دیا ہے اسے علم تھا کہ دائی ترتیب میں اس سے قبل دس سورتیں درج ہوں گی.اسی طرح سورۃ حج میں آیت ہے أُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ (الحج:31) اب اس آیت
میں جو مضمون بیان ہورہا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے تم پر یہ مضامین حلال وحرام کے بیان کیے جاچکے ہیں.اس آیت
میں جو حوالہ دیا جارہا ہے وہ ماقبل مضامین کا ہے اور موجودہ ترتیب میں یہ مضامین سورۃ حج سے قبل کی سورتوں میں
ہی بیان ہوئے ہیں.یعنی سورۃ البقرۃ، مائدۃ ، انعام نجل اور اس سورت کے بعد سورۃ الناس کی ”س“ تک یہ
مضامین بیان نہیں ہوئے جس سے واضح ہو جاتا ہے کہ موجودہ ترتیب خدا تعالیٰ کی مقرر فرمودہ ہی ہے اور بدلی
نہیں گئی کیونکہ خدا تعالیٰ موجودہ ترتیب کے حوالہ سے ہی بات کر رہا ہے.پس صحابہ نے قرآن کریم کی جو بھی
ترتیب پیش کی وہ وہی تھی جو خدا تعالیٰ کی مقرر فرمود تھی.سورتوں کی ترتیب کے تو قیفی ہونے پر سورتوں
کا باہمی تعلق اور ترتیب مضامین قرآن کریم کی ایک عظیم الشان
اندرونی گواہی اور الہی شہادت ہے.مثلاً سورۃ الفاتحہ کے تمام تر مضامین سورۃ البقرۃ میں قدرے تفصیل سے بیان
ہوئے ہیں.اگر سورتوں میں کوئی ترتیب نہیں تھی تو پھر ان کے مضامین کیسے ایک دوسرے سے مربوط ہو گئے؟ اسی
طرح مقطعات کے حوالہ سے سورتوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے.قرآن کریم میں ایک جیسے مقطعات کی سورتیں
ایک ترتیب سے درج ہیں.سورتوں کی ترتیب پر احادیث اور روایات سے دلائل
یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ زمانہ نبوی میں بھی قرآن مجید کی سورتوں کی ایک معروف ،مشہور اور مستعمل
ترتیب ضرور تھی جو ترتیب نزول سے مختلف تھی.اسی ترتیب کے مطابق حفاظ تلاوت کرتے ، اسی کے مطابق
نمازوں میں تلاوت ہوتی تھی اور ہر سال رمضان میں اسی ترتیب کے مطابق جس قدر حصہ قرآن نازل ہو چکا
ہوتا تھا، جبریل علیہ السلام آنحضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے ساتھ اس کا دور مکمل کیا کرتے تھے اور اپنی زندگی میں
آنے والے آخری رمضان میں آپ نے ایک کی بجائے دومرتبہ دور مکمل کیا.چنانچہ بخاری میں ہے کہ:
عَنْ عَائِشَةَ عَنْ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَام أَسَرَّ إِلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَن جِبْرِيلَ كَانَ يُعَارِضُنِي بِالْقُرْآنِ كُلِّ سَنَةٍ وَإِنَّهُ عَارَضَنِي الْعَامَ مَرَّتَيْنِ
وَلَا أُرَاهُ إِلَّا حَضَرَ أَجَلِي
صلى الله
بخاری کتاب فضائل القرآن باب كان جبريل يعرض القرآن على النبى عادل
العلي
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضرت فاطمہؓ سے روایت کرتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
Page 201
قرآن کریم میں تحریف کے الزامات کے جواب
185
نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام ہر سال ماہ رمضان میں میرے ساتھ قرآن کریم کا دور مکمل کرتے
تھے اور اس سال دومرتبہ دور مکمل کیا ہے.ضرور میری وفات کا وقت قریب ہے.اسی طرح بخاری کی ہی روایت ہے:
حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے سامنے ہر سال ایک مرتبہ
قرآن کریم پیش کیا جاتا تھا اور جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال دو مرتبہ آپ کے
سامنے قرآن کریم پیش کیا گیا.(بخاری کتاب فضائل القرآن باب كان جبريل يعرض القرآن على النبي عبد
الله
اسی طرح ایک اور روایت میں ہے:.ان جبريل كان يعارضنى القرآن كل سنة مرة و أنه عارضني الآن مرتين
(زرقانی شرح مواهب الدنيه جلد ٨ صفحه ٢٦٣،٢٥٠)
آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل ہر سال ساتھ میرے ساتھ قرآن کریم کا دور
کرتا اور اس ( یعنی آخری ) سال دومرتبہ دور کیا.کتب حدیث میں کثرت سے ملنے والی اس مستند حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ یقینا سورتوں کی کوئی نہ کوئی
ترتیب تو ضرور تھی جس کے مطابق یہ دہرائی کی جاتی تھی نیز کاتپ رسول حضرت زید بن ثابت بھی اس الْعُرُضَةُ
الاخيرة ، یعنی آخری دور قرآن میں شریک تھے اور اپنی وفات تک لوگوں کو اسی ترتیب سے قرآن پڑھایا کرتے
تھے.حضرت ابو بکر اور حضرت عثمان کے عہد خلافت میں جمع قرآن کے لیے آپ پر اعتماد کرنے کی ایک وجہ آپ کو
حاصل ہونے والی یہ سعادت بھی تھی.یہ وہ ترتیب تھی جو آنحضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم اللہ تعالیٰ کی راہنمائی کے تحت
نزول کے ساتھ ساتھ لگارہے تھے اور اسی کو رائج فرمارہے تھے.البرهان في علوم القرآن جزء اول صفحه (237)
پس ان روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ جس ترتیب میں قرآن کریم جمع کیا گیا وہ صحابہ نے اپنی صوابدید پر اپنی
مرضی سے نہیں لگائی تھی بلکہ الہی راہنمائی اور منشا کے عین مطابق آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لگوائی تھی اور کاتبین
وحی کو آپ اسی ترتیب سے قرآن کریم لکھواتے اسی ترتیب سے حفظ کرواتے.ہر رمضان میں رسول کریم جبرائیل
کی معیت میں اسی ترتیب کے ساتھ قرآن کریم کا دور کمل فرماتے اور یہی ترتیب آج بھی رائج ہے.حضرت مرزا طاہر احمد خلیفہ امسیح الرابع رحمہ اللہ فرماتے ہیں.رمضان المبارک میں اس وحی کا آغاز ہوا ہے اور پھر جتنا جتنا قرآن کریم نازل ہوتا رہا
رمضان المبارک میں اس کی باقاعدہ دہرائی ہوتی رہی اور جب سے قرآن کریم کا آغاز ہوا ہے
Page 202
الذكر المحفوظ
186
اس کے بعد ہر اگلے رمضان میں جبریل علیہ السلام آنحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی خدمت
میں حاضر ہوتے تھے اور اس وقت تک جتنی وحی نازل ہو چکی ہوتی تھی اسے دہراتے تھے.اس
سے بھی پتہ چلتا ہے کہ شروع سے ہی قرآن کریم کے نزول کے ساتھ ترتیب کا ایک دور جاری
تھا اور وہ ترتیب ساتھ ساتھ مکمل ہوتی جا رہی تھی.“
66
( خطبه جمعه فرموده 7 را پریل 1989 )
رسول کریم نے کی لگوائی ہوئی ترتیب بدلی نہیں گئی
یہاں یہ سوال پیدا ہوسکتا ہے کہ مانا کہ ترتیب اللہ تعالیٰ کی ہی لگائی ہوئی تھی یا جو یہ نہیں مانتا کہ قرآن کریم کلام الہی
ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ مانا کہ ترتیب آنحضور نے لگائی تھی مگر کیا دلیل ہے کہ وہ ترتیب اب تک قائم ہے؟
اس سوال کے جواب میں سب سے پہلے تو ہم سورتوں کی ترتیب پر قرآن کریم کی اندرونی گواہی کی طرف
توجہ مبذول کراتے ہیں جس کا ایک نمونہ گزشتہ سطور میں درج کیا گیا ہے.علاوہ ازیں اس حقیقت کے اثبات
میں روایات اور تاریخ سے بھی بہت سے دلائل ملتے ہیں.مثلاً حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے:
ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ وَالْكَهْفِ وَمَرْيَمَ وَطَهِ وَالْأَنْبِيَاءِ إِنَّهُنَّ
منْ الْعَتَاقِ الْأَوَل وَهُنَّ مِنْ تَلَادِي
(بخاری کتاب فضائل القرآن باب تاليف القرآن
سورتہائے بنی اسرائیل کہف، مریم ، طہ، انبیاء اعتماق اول میں سے ہیں اور میرا خزانہ ہیں.موجودہ ترتیب میں یہ سورتیں اسی ترتیب سے ہیں.پھر ذکر ملتا ہے کہ ایک دفعہ آنحضور نے ایک ہی تہجد میں
قرآن شریف کی پہلی پانچ سورتوں یعنی سورت بقرہ ال عمران، نساء، مائدہ یا انعام کی جو مجموعی طور پر قرآن کریم کے پنچم
حصہ کے برابر بنتی ہیں، اکٹھی بالترتیب قراءت فرمائی تھی (ابو داؤد کتاب الصلوة باب مايقول الرجل في ركوعه وسجوده )
ترمذی میں ہے کہ ایک دفعہ آپ نے صلوۃ الکسوف پڑھاتے ہوئے بالترتیب بقرہ ، ال عمران، نساء اور مائدہ کے
کچھ حصے تلاوت فرمائے ( ابواب الجمعة باب ماجاء في صلاة الكسوف ) آج بھی یہ سورتیں اسی ترتیب سے ہیں.اسی طرح صحابہ کثرت سے سبع طوال کی اصطلاح استعمال کرتے تھے جس سے قرآن کریم کی سورۃ الفاتحہ
کے بعد پہلی سات سورتیں مراد ہوتی تھیں جو آج بھی اسی ترتیب سے ہیں.اتقان في علوم القرآن نوع ثامن عشر جمعه و ترتیبه، فصل سوم صفحه 63)
بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنھا کی روایت ہے:
عن
كفيه ثم
عائشة ان النبي ﷺ كان اذا اوى لى فراشه كل ليلة جمع
نفث فيهما فقرأ فيهما قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ وقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وقُلْ أَعُوذُ
Page 203
قرآن کریم میں تحریف کے الزامات کے جواب
187
بِرَبِّ النَّاسِ (بخاری کتاب تفسیر القرآن باب فضل المعوذتين)
حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے ہاں ہوتے تو ہر رات
سوتے وقت بستر پر لیٹ کر ہمیشہ اپنی ہتھیلیوں پر قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اور قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ
الْفَلَقِ اور قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ پڑھ کر پھونکتے.بخاری میں ایک مشہور واقعہ درج ہے جس میں یہ ذکر ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں ایک
صحابی نے نماز پڑھاتے ہوئے سورۃ بقرہ کی تلاوت شروع کی پھر وہ ختم ہوئی تو سورۃ آل عمران شروع کر دی.(بخاری
کتاب الصلوۃ) وہ صحابی اسی ترتیب سے سورتیں پڑھ رہے تھے جو کہ آج بھی رائج ہے.پھر وہ مشہور واقعہ ہے کہ جب ایک صحابی ام کلثوم بن الہدم نماز پڑھاتے ہوئے سورۃ الفاتحہ کے بعد کسی بھی
سورت کی تلاوت سے قبل سورۃ الاخلاص کی تلاوت کیا کرتے تھے.اُن کو صحابہ نے ٹوکا.(صحیح بخاری کتاب
الاذان باب الجمع بين السورتين في ركعة) حافظ ابن حجر عسقلانی اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ:
ان صنيعه ذلك خلاف ما الفوه من
النبي
(فتح الباری شرح بخاری کتاب الاذان باب الجمع بين السورتين في ركعة)
یعنی اُن کا یہ فعل اس ترتیب کے خلاف تھا جو صحابہ نے آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا
اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے دور میں ترتیب قرآن کا اس لحاظ سے
خاص خیال رکھا جاتا تھا کہ تلاوت کے وقت بلا وجہ ترتیب سور کو نہ بدلا جائے.پھر قرآن کے تحریر کرنے کے بارہ میں احادیث میں تالیف کا ذکر ملتا ہے.چنانچہ کتب حدیث میں کثرت سے
قرآن کریم کی تالیف کے ابواب درج کیے گئے ہیں.مثلاً بخاری میں کتاب مجمع القرآن باب تالیف القرآن میں امام
بخاری نے مختلف روایات درج کی ہیں جن میں رسول کریم کے زمانہ میں تالیف قرآن کا ذکر ہے.عربی میں تالیف
سے مراد ہے ترتیب سے جمع کرنا.پس امام بخاری کا اپنی صحیح میں پورا ایک باب اس موضوع پر باندھنا اس بات کی
دلیل ہے کہ آپ کے نزدیک ان روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی ایک ترتیب ضرور تھی.رمضان میں
جبریل کے ساتھ قرآن کریم کی دہرائی کا ذکر بھی اسی باب کے تحت کیا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے نزدیک
بھی اس دہرائی کی ایک خاص ترتیب تھی.قرآن کے بارہ میں تالیف کا لفظ حضرت امام بخاری نے ہی پہلی مرتبہ
استعمال نہیں کیا بلکہ کاتب وحی حضرت زید بن ثابت بھی یہی لفظ اپنی ایک روایت میں استعمال کرتے ہیں:
كنا عند رسول الله ﷺ نؤلف القرآن في الرقاع
(ترمزی کتاب المناقب عن رسول الله باب في فضل الشام و اليمن)
(الاتقان: الجزء الاول ؛ النوع الثامن عشر ؛ جمع القرآن و ترتيبه ، صفحه:58)
(تفسير روح المعانى جزء اول صفحه 21 مكتبه امدادیه ملتان)
Page 204
الذكر المحفوظ
188
یعنی ہم رسول کریم کے عہد مبارک میں ٹکڑوں پر قرآن کریم تالیف کیا کرتے تھے.علامہ سیوطی لکھتے ہیں:
و اخرج عن ابن وهب قال سمعت مالكا يقول انما الف القرآن على ما
كانو يسمعون من النبي ﷺ (وقال) بغوى في شرح السنة لصحابه
رضی الله عنهم جمعوا بين الدفتين القرآن الذي انزله الله على رسوله
من غير ان زادوا او نقصوا منه شيئا خوف ذهاب بعضه بذهاب حفظته
فكتبوه كاملا كما سمعوا من رسول الله ﷺ من غير ان قدموا شيئا او
اخروا او وضعوا له ترتيبا لم يأخذوه من رسول الله ﷺ و كان الرسول
الله الله يلقن اصحابه ويعلمهم ما نزل عليه من القرآن على الترتيب
الذي هو الآن في مصاحفنا بتوقيف جبريل اياه...فثبت ان سعی
الصحابه كان في جمعه في موضع واحد لا في ترتيبه
(اتقان في علوم القرآن: نوع ثامن عشر جمعه و ترتيبه، فصل سوم صفحه 61)
وھب سے روایت ہے کہ انہوں نے مالک کو یہ کہتے سنا کہ قرآن کریم اُسی ترتیب پر ہوئی
ہے جس پر (صحابہ) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنتے تھے.علامہ بغوی سے شرح السنتہ میں لکھا
ہے کہ صحابہ نے قرآن کریم کو اُسی ترتیب سے مجلد صورت دی تھی جس ترتیب سے اللہ تعالیٰ نے
اپنے رسول پر نازل فرمایا تھا.انہوں نے نہ تو اس میں کوئی تقدیم و تاخیر کی اور نہ ہی اپنی طرف
سے کوئی ایسی ترتیب لگائی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ سیکھی تھی.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے صحابہ کو اسی ترتیب کی تلقین کیا کرتے تھے اور وہی ترتیب سکھایا کرتے تھے جو آج بھی
ہمارے مصاحف میں پائی جاتی ہے اور جو آپ نے جبریل کی وساطت سے سیکھی تھی.پس یہ
امر ثابت شدہ ہے کہ صحابہ کی جمع قرآن کی کوشش کا تعلق ایک جگہ جمع کرنے سے تھا اور ترتیب
سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا.پھر لکھتے ہیں :
و اخرج ابن داشتة في كتاب المصاحف من طريق ابن وهب عن
سلیمان بن بلال قال سمعت ربيعة يسأل لم قدمت البقرة وآل عمران و
قد نزل قبلهما بضع و ثمانون سورة بمكة و انما انزلتا بالمدينة فقال قدمتا
Page 205
قرآن کریم میں تحریف کے الزامات کے جواب
189
و الف القرآن على علم ممن الفه به و من كان معه فيه و اجتماعهم على
علمهم بذلك فهذا مما ينتهى اليه ولا يسل عنه
اتقان في علوم القرآن نوع ثامن عشر جمعه و ترتیبه، فصل سوم صفحه 63)
ابن داشتہ نے کتاب المصاحف میں ابن وہب کے حوالہ سے سلیمان بن بلال سے روایت
کی ہے کہ میں نے ربیعہ سے کسی کو یہ سوال کرتے ہوئے سنا کہ بقرۃ اور ال عمران کی سورتیں
کیوں مقدم کی گئیں حالانکہ اس سے پہلے مکہ میں اسی (80) سے زائد سورتوں کا نزول ہو چکا تھا
اور یہ دونوں مدینہ میں آکر نازل ہوئیں؟ ربیعہ نے جواب دیا ” قرآن کی تالیف ان لوگوں کے
علم پر ہوئی ہے جو اس کے مؤلف کے دیکھنے والے اور اس کی تالیف میں مؤلف کے ساتھ موجود
تھے اور ان لوگوں کا اس کا علم رکھنے کے ساتھ اس پر اجماع بھی ہو گیا تھا.لہذا یہی بات اس بارہ
میں کافی ہے اور اس سے زیادہ سوال کرنا غیر ضروری ہے.مشہور شیعہ مفسر ابو فضل بن الحسن الطمرسی اپنی کتاب مجمع البیان میں علامہ مرغی کا قول اپنی تحقیق کی تائید میں
پیش کرتے ہیں کہ :
وكذالك القول في كتاب المزني.....ان القرآن علی عہد رسول الله (ص)
مجموعا مؤلفا على ما هو عليه الان واستدل على ذلك بان القرآن كان
يدرس ويحفظ جميعه في ذلك الزمان حتى عين عليه جماعة من
الصحابه في حفظهم له وانه كان يعرض على النبي (ص) و يتلى عليه
الأن جماعة من الصحابة مثل عبد الله بن مسعود و أبي بن كعب و
غيرهما ختمو القرآن على النبي (ص) عدة ختمات و كل ذلك يدل
بادنی تامل على انه كان مجموعا مرتبا غير مبتور ولا مبثوت و ذكر ان من
خالف في ذالك من الامامية و حشويه لا يعتد بخلافهم فان الخلاف في
ذلك مضاف الى قوم من اصحاب الحديث نقلو اخبارا ضعيفة.(ابوالفضل بن الحسن الطبرسی مجمع البیان جلد اول: مقدمة الكتاب: الفن
الخامس صفحه 15 الناشر مكتبه علميه الاسلاميه ملتان)
یعنی اسی کے مطابق علامہ مزنی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں....کہ قرآن کریم دراصل رسول
کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے دور میں ہی جمع ہو گیا تھا اور اسی طرح تالیف ہو گیا تھا جیسا کہ
آج کے دور میں ہے اور اس پر یہ دلیل ہے کہ قرآن مجید مکمل و مجموعی طور پر اس زمانہ میں پڑھا
Page 206
الذكر المحفوظ
190
جاتا تھا اور حفظ کیا جاتا تھا اور صحابہ کی ایک جماعت عبد اللہ بن مسعود اور ابی بن کعب وغیرہ نے
چند مرتبه قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ختم کیا اور ان باتوں پر ادنی تامل اور
تفکر سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ قرآن کریم مدون و مرتب ہے اور غیر مرتب نہیں ہے.اور یہ بات بھی
یا در کھنے کے قابل ہے کہ امامیہ اور حشویہ میں سے جن لوگوں نے اس رائے کی مخالفت کی ہے ان
کی باقی لوگوں کے مقابل میں کوئی حقیقت اور شمار نہیں ہے کیونکہ یہ اختلاف صرف اصحاب
حدیث کے ضعیف خبریں نقل کرنے کی وجہ سے ہوا ہے.اس کے بعد علامہ آلوسی اپنی تائید میں علامہ ابوبکر الانباری اور علامہ کرمانی وغیرہ کا قول درج کرتے ہیں.علامہ ابوبکر انباری کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سارا قرآن سماء دنیا تک اتارا پھر ہیں
سے زائد برسوں میں مختلف حصوں میں تقسیم کر کے (نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا.جب
کوئی معاملہ وقوع پذیر ہوتا تو مسئلہ کی وضاحت کے لیے کوئی سورت نازل ہو جاتی یا کوئی
شخص کوئی سوال پوچھتا تو اس کے جواب کے لیے کوئی آیت اترتی اور جبریل علیہ السلام
آنحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم کو اس آیت یا سورۃ کی ترتیب کے لحاظ سے جگہ بتاتے.یوں
ترتیب قائم ہوتی گئی.پس اب اگر کوئی اس ترتیب میں سے کسی حصہ کو آگے پیچھے کرے گا تو
قرآن مجید کے مضامین کے ربط کو توڑ دے گا.اور علامہ کرمانی کا قول ہے کہ سورتوں کی جو ترتیب اب ہے یہی ترتیب اللہ تعالیٰ کے پاس
لوح محفوظ میں بھی ہے اور اسی ترتیب کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم ہر سال جبریل
کے ساتھ اس حصہ کا دور فرمایا کرتے تھے جو اس وقت تک جبریل علیہ السلام کے ذریعہ آپ پر
نازل ہو چکا ہوتا تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ کے آخری سال
جبریل علیہ السلام کے ساتھ اسی ترتیب کے مطابق دو دفعہ دور مکمل فرمایا.نیز طیبسی نے بھی یہی
کہا ہے اور علما کے ایک جم غفیر سے بھی یہی قول مروی ہے.(ابوالفضل بن الحسن الطبرسی مجمع البیان جلد اول: مقدمة الكتاب: الفن
الخامس: جمع القرآن صفحه 15 الناشر مكتبه علميه الاسلاميه ملتان)
تفسیر خازن میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم اسی ترتیب سے صحابہ کو سکھایا تھا جوتر تیب
جبریل نے سکھائی تھی.(تفسير خازن الجزء الأول مقدمة الكتاب صفحه 9)
صاحب البرہان نے اس بارہ میں امام بیہقی کا یہ قول نقل کیا ہے کہ:
Page 207
قرآن کریم میں تحریف کے الزامات کے جواب
191
ہم زید بن ثابت سے روایت درج کر آئے ہیں کہ قرآن مجید کی ترتیب زمانہ نبوی میں
ہوئی، اسے ایک ہی جلد میں جمع کرنے کا کام حضرت ابو بکر کے زمانہ میں ہوا اور حضرت عثمان
کے دور میں اسے متعدد نسخوں میں نقل کیا گیا.البرهان في علوم القرآن جزء اول صفحه 235)
اتقان میں علامہ سیوطی نے کثرت کے ساتھ ایسی روایات، احادیث اور آراء درج کی ہیں جن میں علما
اور بزرگان کے اس عقیدہ کا اظہار موجود ہے کہ سورتوں کی ترتیب آیات کی ترتیب کی طرح توقیفی ہے یعنی الہی
راہنمائی کے مطابق آنحضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے خود لگوائی ہے.علامہ سیوطی کا اپنا رجحان بھی اسی طرف ہے
کہ سورتوں کی دائمی ترتیب تو قیفی ہے.(الاتقان جز اول ؛ النوع الثامن عاشر؛ الفصل؛ جمعه ترتیبه صفحه 58)
پس روایات اور احادیث کا مطالعہ کرنے سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ سورتوں کی معروف ترتیب تھی جو
تو قیفی تھی اور آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں لگائی گئی تھی اور آپ نے امت کو سکھا دی تھی.جبکہ دوسری
جانب کہیں کوئی ایسی روایت تو نہیں ملتی جس میں خصوصیت سے یہ ذکر ہو کہ سورتوں کی کوئی خاص ترتیب نہیں تھی
نہ ہی کوئی ایسی روایت ملتی ہے جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے سورتوں کی ترتیب لگانے کے ضمن
میں صحابہ کو کوئی نصیحت فرمائی ہو.جبکہ بہت سی ایسی روایات ملتی ہیں کہ کئی سورتوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی
ترتیب سے تلاوت کیا کرتے تھے جس ترتیب سے وہ آج بھی موجود ہیں.اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ رسول کریم
صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے دور میں سورتوں
کی کوئی نہ کوئی ترتیب ضرور تھی.تمام سورتوں کی ترتیب رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے ثابت نہ ہونے کی وجہ سے یہ نتیجہ نکالنا درست
نہیں کہ کوئی ترتیب نہیں تھی.اگر تمام سورتوں کی ترتیب کے بارہ میں روایات نہ بھی ملیں بلکہ چندسورتوں کے بارہ
میں ہی ملیں ، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال جبرائیل کی معیت میں قرآن کریم کا
دور کیا کرتے تھے تو کوئی وجہ نہیں کہ یہ نتیجہ نہ نکالا جائے کہ قرآن کریم کی سورتوں کی ایک خاص ترتیب تھی جس کے
مطابق یہ دور ہوتا تھا اور جس کے مطابق صحابہ تلاوت کیا کرتے تھے اور نمازوں اور تراویح وغیرہ میں تلاوت ہوا
کرتی تھی.آیات کے بارہ میں بھی تو روایات میں اصولی طور پر یہ طریق بیان کر دیا گیا کہ رسول کریم نئی نازل
ہونے والی ہر آیت کی مخصوص جگہ کی وضاحت فرماتے اور بتاتے کہ فلاں سورت میں جہاں فلاں مضمون
بیان ہورہا ہے وہاں فلاں آیت سے قبل یا بعد میں یہ آیت لکھ دو.ایسا نہیں ہے کہ آج تمام آیات کی ترتیب
آنحضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے ثابت ہے.راویوں نے سمجھانے کے لیے چند مثالیں محفوظ کرلیں ساری
آیات کی ترتیب بیان نہیں کی.اسی طرح ترتیب سور کے ضمن میں بھی راویوں نے چندسورتوں کی مثال پیش
Page 208
الذكر المحفوظ
192
کر کے ترتیب سور کا ذکر کر دیا.یہ تمام روایات ترتیب سور کا ذکر تو کرتی ہیں مگر چونکہ یہ ترتیب رائج اور مستعمل تھی
اور اس کے علاوہ اور کوئی ترتیب نہیں تھی اس لیے تمام سورتوں کی ترتیب کا ذکر نہیں کیا گیا بلکہ جس طرح آیات
کے بارہ میں اصولی طور پر ایک علم آگے منتقل کر دیا اسی طرح سورتوں کے بارہ میں اصولی طور پر بتادیا کہ ان کی
ترتیب بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الہی رہنمائی کے مطابق لگائی.اگر ایک سے زیادہ ترتیبیں رائج ہوتیں
تو ضرور ان کا الگ الگ ذکر کیا جاتا یا پھر ضر ور سورتوں کا کسی دوسری ترتیب سے بھی ذکر ملتا نہ کہ ہمیشہ اسی ترتیب
سے کہ جو آج بھی رائج ہے.تمام روایات کے مجموعی مطالعہ سے واضح ہوتا ہے کہ کوئی نئی ترتیب نہیں سکھائی گئی
بلکہ کسی ایک مخصوص ترتیب کا ذکر کیا گیا ہے.جیسا کہ اگر کوئی کہے کہ فلاں شخص کار سے لا ہور گیا تو اس سے یہ
بات واضح ہو جائے گی کہ کہنے والے اور سننے والے کو علم ہے کہ کار کیا چیز ہے اور لاہور کیا ہے.اس سے یہ مراد
نہیں ہوگا کہ سنانے والے کو سکھایا جا رہا ہے کہ کار کوئی چیز ہے اور لاہور کوئی جگہ ہے.صرف ایک خبر دی جارہی
ہے.اسی طرح ان روایات میں بھی صرف خبر دی جارہی ہے اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب ایک ترتیب
ہو اور کہنے والے اور سننے والے کو اس ترتیب کا علم ہو.پس اگر تمام روایات میں کچھ سورتوں کا ایک ہی ترتیب
سے ذکر ملتا ہے تو اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ کوئی ترتیب رائج ضرور تھی اور جب وہی ترتیب آج بھی رائج ہے
تو کیا یہ واضح ثبوت نہیں کہ آج بھی قرآن کریم کی ترتیب وہی ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی
اور بدلی نہیں گئی؟ پھر جب چند سورتوں کی ترتیب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے تو اس آیت وَمَا
يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى.إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى (النجم :4,5) کی موجودگی میں قرآن کریم کی ترتیب توقیفی
ترتیب ہی مانی جائے گی.جیسا کہ حضرت امام رازی کی رائے گزرچکی ہے.یہ بات بھی زیر نظر رہے کہ اگر سورتوں کی ایک ترتیب نہ ہوتی تو پھر کوئی شخص قرآن کریم کی تلاوت آسانی
سے نہ کر پاتا.اس بات کو یوں سمجھا جاسکتا ہے آپ 1 سے لے کر 114 تک کبھی بنا کسی ترتیب کے گنتی گنیں.مثلاً
59،83،67، 81،39،01، 73 وغیرہ.اس طرح اول تو آپ گن ہی نہیں سکیں گے اور اگر بزعم خود کسی طرح گن
کر پورا کر بھی لیں تو سننے والا اگر غور سے سُن رہا ہو تو بتائے گا کہ آپ نے فلاں فلاں عدد چھوڑ دیا ہے بلکہ اسی
طرح اگر آپ بنا کسی ترتیب کے لکھنا شروع کر دیں اور جب اپنے خیال کے مطابق مکمل لکھ لیں تو ان ہندسوں پر
دوبارہ نظر ڈالیں.آپ دیکھیں گے کہ کتنے ہی عدد گنتی سے رہ گئے ہیں.پس 1 سے لے کر 114 تک بلا ترتیب
گنتی گننا ممکن نہیں کجا یہ کہ قرآن کی 114 سورتوں کی زبانی تلاوت کی جائے.اگر سورتوں میں کوئی ترتیب نہ ہوتی تو پھر ضرور تھا کہ ترتیب لگاتے وقت اختلاف رائے ہوتا.کوئی کسی سورت
کو آگے رکھتا اور کوئی کسی کو.مثلاً کچھ سورتوں کی ترتیب لگاتے وقت سب سے پہلے یہ مد نظر رکھا جاتا کہ ان کی
ترتیب کتنے طریق پر لگائی جاسکتی ہے.فرض کیجیے کہ تین سورتوں کی ترتیب کا مسئلہ ہے.اگر ان کی ترتیب کے
Page 209
قرآن کریم میں تحریف کے الزامات کے جواب
193
مختلف انداز دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ ان کو (6 = 3 × 2 ) چھ طریقوں سے مرتب کیا جاسکتا ہے.اگر یہی معاملہ
چھ سورتوں کی ترتیب میں پیش آئے تو ان کی 720 ترتیبیں لگائی جاسکتی ہیں.اب قاری سوچ لے کہ 114 سورتوں
کی ترتیب میں امکانات کو ہی دیکھا جائے تو ترتیب کے لاتعداد امکانات تک بات جا پہنچتی ہے.پس اگر
سورتوں کی کوئی ترتیب نہ ہوتی تو حضرت ابوبکر کے جمع قرآن کے وقت جھگڑا کھڑا ہوجاتا اور لبی لمبی بحثیں
اُٹھتیں.کیونکہ ناممکن ہے کہ مسلمان قوم جو کہ قرآن کریم کے عشق میں جان کی بازی لگانے کی ان گنت مثالیں قائم
کر چکی تھی اور اس معاملہ میں بہت حساس تھی، بلاوجہ خدا تعالیٰ کی نازل کردہ ترتیب کو بدلنے پر خاموش رہتی اور
آرام سے ایک غیر معروف ترتیب پر متفق ہو جاتی.پس بہت خوفناک جھگڑا کھڑا ہوجاتا کیونکہ مختلف مجوزہ ترتیبیں
سامنے آتیں.مختلف ترتیبوں کے حامی مختلف گروہ بن جاتے.مثلا ترتیب نزولی یا سورتوں کے حجم کے لحاظ سے
ترتیب.اس صورت میں بھی دوتر تی ہیں ممکن تھیں یعنی بڑی پہلے اور چھوٹی بعد میں یا اس کے الٹ یعنی چھوٹی پہلے
اور بڑی بعد میں.پھر کئی کہنے والے یہ بھی کہتے کہ جب کوئی ترتیب ہے ہی نہیں تو اس جھگڑے سے بہتر ہے کہ
اسی ترتیب میں سورتوں کو لکھ لو جس ترتیب میں وہ نازل ہوئی ہیں.کیوں بلاوجہ ترتیب نزولی کو بدلتے ہو اور چند
صحابہ کی رائے باقی صحابہ اور امت پر ٹھونستے ہو؟ اور پھر ترتیب بدلنے والے صحابہ دلائل دیتے اور پھر فیصلہ کیا جاتا
کہ کون سی ترتیب بہتر ہے اور آیا بہتر ترتیب رکھی جائے یا وہی ترتیب رہنے دی جائے جو کہ نزول کے مطابق
ہے.پھر ان دلائل کا روایات میں ذکر ہوتا اور بعد کے علما یہ بحث نہ کرتے کہ ترتیب تو قیفی تھی یا صحابہ کی لگائی ہوئی
تھی.بلکہ یہ بحثیں اُٹھتیں کہ دونوں گروہوں میں سے زیادہ درست بات کون سا گر وہ کر رہا تھا.اگر نئی ترتیبیں
لگانے والے گروہ حق پر تھے تو ان میں سے بہترین ترتیب کس کی تھی؟ بعد میں بھی تو علما نے صرف اسی بات پر لبی
لمبی بحثیں کی ہیں کہ ترتیب تو قیفی ہے یا صحابہ نے لگائی ہے تو پھر جب ترتیب لگائی جارہی تھی تو کیا اس وقت
اختلافی بحثیں نہیں اُٹھنا چاہئیں تھیں؟ مگر ایسے کسی جھگڑے کا کھڑا نہ ہونا اور ایک باڈیڑھ سال کے قلیل عرصہ میں
امت کا اتفاق رائے سے ایک عظیم الشان کارنامہ سرانجام دے دینا اس بات کی دلیل ہے کہ پہلے سے ایک
ترتیب موجود تھی جس پر ساری امت متفق تھی.اگر یہ کام صحابہ کی صوابدید پر چھوڑا جاتا تو اتنا عظیم اختلاف پیدا
ہوتا کہ تاریخ میں اس کا ذکر ضرور آتا.آنحضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی نگرانی میں لکھے ہوئے قرآن کریم کے
حضرت ابوبکر کے زمانہ میں دوبارہ لکھنے پر اس قدر احتیاط برتی گئی تو پھر کیسے ممکن تھا کہ ترتیب لگاتے وقت صحابہ
سے رائے نہ لی جاتی ؟ لازماً اختلاف پیدا ہونا چاہیے تھا اور کئی ایک گروہ بنے چاہیئیں تھے.پھر ان گروہوں میں
بحث و مباحثہ کے بعد فیصلہ ہونا چاہیے تھا مگر اتنی خاموشی سے بنا کوئی دوسری بات کیسے سارے صحابہ کا اس ترتیب
پر متفق ہو جانا بتا تا ہے کہ ترتیب کے ضمن میں کوئی دوسری رائے تھی ہی نہیں اور ایک ہی مروج اور متفقہ ترتیب تھی
اور وہی آج بھی مروج ہے کیونکہ آج بھی وہی ترتیب ہے جو روایات سے ثابت ہوتی ہے اور ایسا ذکر کہیں نہیں ملتا
Page 210
الذكر المحفوظ
194
کہ قرآن کریم کی ترتیب کبھی بدلی گئی ہو.پس حضرت ابو بکڑ نے ترتیب قرآن کے باب میں کوئی ایسا قدم نہیں
اُٹھایا جو نیا تھا بلکہ ترتیب قرآن کے ضمن میں کوئی نیا قدم اُٹھایا ہی نہیں.حضرت عثمان کے زمانہ میں بھی قرآن کریم کی ایک قراءت پر امت کو جمع کرتے وقت بھی ترتیب کی کوئی
بحث نہیں اُٹھی اور وہی ترتیب برقرار رکھی گئی جو پہلے سے چلی آرہی تھی.غور طلب امر یہ ہے کہ اختلاف قراءت پر
تو صحابہ میں بحثیں اُٹھیں جو آنحضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے ثابت تھا تو کیا ترتیب بدلنے پر صحابہ خاموش رہ سکتے
تھے؟ ضرور اس کا ذکر بھی روایات میں آنا چاہیے تھا.ضرور ذکر ملنے کی بات کس درجہ مضبوط ہے اس کا اندازہ وہی
کر سکتا ہے جو اسلامی روایات کا کچھ مطالعہ رکھتا ہے.اہل علم جانتے ہیں کہ اسلامی تاریخ میں کسی چھوٹی سے چھوٹی
بات کو بھی مؤرخین اور راویوں نے ذکر کیے بغیر نہیں چھوڑا اور اس کا اعتراف مستشرقین بھی کرتے ہیں.پس کیسے
ممکن ہے کہ اتنے باریک بین مؤرخین اور راوی ترتیب قرآن کے ضمن میں اتنی اہم بحث کو کلیہ بھول جاتے اور
دوسری طرف ایسے مخالفین بھی خاموش ہیں جن کی مخالفت کی مثال تاریخ مذاہب دینے سے قاصر ہے اور ترتیب
کے ضمن میں ابتدائی دور میں جبکہ ترتیب کی بحث اُٹھنی چاہیے تھی، کوئی اعتراض نہیں کرتے اور باوجود اس کے کہ
قرآن
ترتیب نزولی کے لحاظ سے بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد تیار تھا ( حضرت علی
نے قریباً چھ ماہ کے عرصہ میں یہ نسخہ تیار کیا تھا پھر بھی امت محمدیہ میں کوئی اختلاف تو کیا سرسری سا بھی ذکر نہیں ملتا
کہ یہ آواز اُٹھی ہو کہ قرآن کی ترتیب، ترتیب نزولی ہونی چاہیے اور بلا وجہ بدلنی نہیں چاہیئے.حضرت علیؓ جنہوں
نے ترتیب نزول کے مطابق قرآن کریم کا نسخہ تیار کیا تھا کو بھی حضرت ابوبکر اور عثمان رضی اللہ عنہما کے کام سے پورا
اتفاق تھا.(روح المعانی جلد اول زیر عنوان جمع القرآن صفحه 23 مکتبہ امدادیہ ملتان)
پس ثابت ہوا کہ یہ واضح حقیقت تھی اور گویا صحابہ کا اس پر اجماع تھا کہ قرآن کریم کی سورتوں کی ایک دائمی
ترتیب ہے اور وہ ترتیب، ترتیب نزولی نہیں ہے اور وہی دائمی ترتیب رسول کریم سے لے کر اب تک رائج ہے اور
اس کے بدلنے کا سوال
کبھی نہیں اُٹھا.علامہ سیوطی ابو بکر بن انباری کا قول درج کرتے ہیں:
قال ابو بکر بن الانباری انزل الله القرآن كله الى سماء الدنيا ثم فرقه في
بضع و عشرين فكانت السورة تنزل لامر يحدث والآية جوابا
لمستخبر و يوقف جبريل النبي ﷺ على موضع الآية والسورة فاتساق
السور كاتساق الآيات و الحروف كله عن النبي ﷺ فمن قدم سورة او
اخرها فقد افسد نظم القرآن.(اتقان في علوم القرآن نوع ثامن عشر جمعه و ترتیبه، فصل سوم صفحه 62)
Page 211
قرآن کریم میں تحریف کے الزامات کے جواب
195
ابوبکر بن انباری فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سارا ایک ہی بارسماء دُنیا پر نازل کیا
اور پھر اسے بیس سے زائد برسوں میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے حسب موقع آیت آیت اور سورت
سورت کر کے نازل کیا.جبریل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آیات اور سورتوں کی ترتیب بتاتے
تھے.پس سورتوں کی ترتیب بھی آیات اور حروف کی ترتیب کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
طرف ہی منسوب ہے اور جو بھی کسی ایک بھی سورۃ کو آگے یا پیچھے کرے گا تو وہ قرآن کریم کا
حسنِ نظم خراب کرے گا.پس یہ امر واضح ہے کہ تالیف قرآن، آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی راہنمائی اور نگرانی میں آپ کی حیات مبارکہ
میں ہی صحابہ نے کر دی تھی، اور آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راہنما خود خدا تھا اور ترتیب کے بارہ میں
کبھی بھی کسی قسم کا
کوئی اختلاف نہیں ہوا تھا، بلکہ اجماع ہوا تھا.آخر میں سورتوں کی ترتیب کے تو قیفی ہونے پر ایک اور مضبوط اور
نا قابل تردید ثبوت پیش کر کے آگے بڑھتے ہیں :
قرآن کریم کی احزاب یا منازل میں تقسیم
ترتیب سور کے تو قیفی اور غیر مبدل ہونے ایک بہت بڑا اور نا قابل تردید ثبوت قرآن کریم کی احزاب اور
منازل میں تقسیم ہے.قرآن مجید سات احزاب ( منازل ) میں تقسیم ہے.یہ تقسیم قرآن مجید کی تلاوت کا دور
ایک ہفتہ میں مکمل کرنے کی غرض سے ہے.اس بات کی قطعی ثبوت ملتے ہیں کہ منازل کی یہ تقسیم صحابہ کرام میں
آنحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی مروج تھی.جس سے ترتیب سور کا ایک اہم ثبوت ملتا
ہے.علاوہ ازیں اسی روایت کے مطابق اجزاء یعنی پاروں کی تقسیم بھی ارشاد نبوی کی روشنی میں صحابہ کرام سے ہی
منسوب ہے.چنانچہ روایت ہے:
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ لِى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِقْرَا
الْقُرْآنَ فِي شَهْرٍ قُلْتُ إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً قَالَ فَاقْرَأَهُ فِي سَبْعِ وَلَا تَزِدْ عَلَى ذَالِكَ
(بخاری کتاب فضائل القرآن باب في كم يقرا القرآن)
حضرت عبداللہ بن عمر ورضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم
نے مجھ سے فرمایا کہ قرآن کریم کا ایک دور ایک ماہ میں مکمل کیا کرو.اس پر میں نے عرض کی کہ
میں تو اپنے اندر اس سے بھی جلد دور مکمل کرنے کی ہمت پاتا ہوں.اس پر آنحضور صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا کہ پھر زیادہ سے زیادہ ایک ہفتہ میں ایک دور مکمل کیا کرو اس سے کم وقت میں نہیں.صحابہ نے آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کی تعمیل میں آپ کے دور مبارک میں ہی قرآن کریم کو
Page 212
الذكر المحفوظ
196
سات برابر حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا.چنانچہ روایت ہے:
عن حديقة الثقفي قال فسألنا أصحاب رسول الله صلى الله ﷺ قلنا كيف
تحزبون القرآن قالو نحزبه ثلاث سور و خمس سور و سبع سور و تسع
سور و احدى عشرة و ثلاث عشرة وحزب المفصل من ق حتى نختم
(سنن ابی داؤد کتاب الصلاة باب تحزيب القرآن 1158)
حضرت حذیفہ التفی فرماتے ہیں کہ قبیلہ ثقیف کے مسلمان ایک دفعہ وفد کی صورت میں
آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے..ہم نے صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم
نے قرآن کریم کے احزاب کے بارہ میں سوال کیا تو انہوں نے بتلایا کہ ہم نے تین اور پانچ اور
سات اور نو اور گیارہ اور تیرہ اور پھر سورۃ ق سے آخر قرآن تک سورتوں کے حزب بنائے ہوئے ہیں.اسی مضمون کی حدیث الفاظ کے ادنیٰ سے فرق کے ساتھ مسند احمد : مسند المد ینین اجمعین حدیث اوس بن ابی
اوس اثقفی نمبر 15578 پر درج.اس تقسیم کی تفصیل حسب ذیل ہے.1- الفاتحہ تا النساء ( پہلی چارسورتیں )
2.المائدہ تا التوبه (اگلی پانچ سورتیں )
(انگلی سات سورتیں)
3.یونس تا النحل
4.-4 بنی اسرائیل تا الفرقان ( اگلی نوسورتیں)
5- الشعراء تائيسين (انگلی گیارہ سورتیں)
6- الصافات تا الحجرات ( اگلی تیرہ سورتیں)
7.سورۃ ق تا الناس (اگلی پینسٹھ سورتیں)
حضرت علامہ سیوطی فرماتے ہیں:
فهذا يدل على ان ترتيب السور على ما هو في المصحف الآن كان
علی عہد رسول الله ل ل و ل
ﷺ قال ويحتمل ان الذي كان مرتبا.اتقان في علوم القرآن: نوع ثامن عشر جمعه و ترتیبه، فصل سوم صفحه 63)
تی تقسیم اس بات کی دلیل ہے کہ سورتوں کی ترتیب آج بھی وہی ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کے عہد مبارک میں رائج تھی اور اُس دور میں بھی قرآن کریم کی سورتوں کی یہی ایک ترتیب ہوا
کرتی تھی
علامہ الزرکشی کی بھی یہی رائے ہے.البرهان فی علوم القرآن جز واول صفحہ 311)
عرض الانوار صفحہ 41 42 43 از قاضی عبدالصمد سیوہاروی مطبوعہ حمید برقی پریس دہلی 1359 طبع اوّل)
Page 213
قرآن کریم میں تحریف کے الزامات کے جواب
197
علامہ سیوطی کا رجحان اس طرف ہے کہ سوائے سورۃ تو بہ اور انفال کے باقی تمام سورتوں کی ترتیب
رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے الہی راہنمائی میں لگائی تھی.مذکورہ بالا تقسیم میں یہ دونوں سورتیں بھی شامل
ہیں.نیز جب باقی سورتوں کی ترتیب ان روایات کی روشنی میں نیز عقلا تسلیم کی جاسکتی ہے تو پھر سورۃ تو بہ اور
انفال کی ترتیب کو رسول کریم کی طرف کیوں منسوب نہیں کیا جاسکتا ؟
بعض عیسائی مستشرقین بھی یہ تسلیم کرتے ہیں کہ قرآن
کریم کی سورتوں کی مکمل ترتیب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے خود قائم فرما دی تھی اور اس باب میں بھی کوئی کمی باقی نہ تھی.مثلاً John Burton کہتا ہے:
(the Qur'an as we have it today is) "the text which has
come down to us in the form in which it was organized
and approved by the Prophet....What we have today in
our hands is the Mushaf of Muhammad."
(John Burton, The Collection of the Qur'an, Cambridge:
Cambridge University Press, 1977, p.239-40)
یعنی جو متن ہم تک پہنچا ہے بعینہ اسی صورت میں ہے جو نبی کریم ﷺ نے بذات خود
مرتب اور منظور کیا.آج جو ہمارے ہاتھ میں کتاب ہے یہ دراصل مصحف محمدی
فرانسیسی مستشرق Dr.Maurice Bucaille لکھتے ہیں:
Over a period of twenty years, the Prophet classified
its sections with the greatest of care, as we have seen.The Qur`an represented what had to be written down
during his own life-time and learned by heart to become
part of the liturgy of prayers.(The bible The Quran and Science (translation from French by
Alastair D.Pannel and The Ahthor) Under Heading Conclusions
Pg 250-251)
ہیں سال سے زیادہ عرصہ میں نبی (ﷺ) نے بذات خود حد درجہ احتیاط کے ساتھ اسے
مختلف حصوں میں تقسیم کیا تھا جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں.قرآن وہ چیز ہے جو کہ آپ (ﷺ) کی
حیات مبارکہ میں بطور خاص تحریر کیا جاتا تھا اور ساتھ ساتھ حفظ بھی کیا جاتا تھا تا کہ فرض نمازوں
میں اس کی تلاوت کی جاسکے.ایک دوسری جگہ لکھتے ہیں :
قرآن اُس وحی کی ظاہری صورت ہے جو حضرت جبریل کے ذریعہ (حضرت ) محمد (ﷺ)
کو پہنچی.جس کو فوراً قلمبند کر لیا گیا اور اہل ایمان نے حفظ کر لیا.خود ( حضرت ) محمد (ﷺ)
Page 214
الذكر المحفوظ
66
نے اس کی سورتوں میں ترتیب قائم کی.“
198
(The bible The Quran and Science (translation from French by
Alastair D.Pannel and The Ahthor)Under Heading "The Books of
Old Testament Pg 12)
گزشتہ سطور میں بیان کردہ ثبوتوں کا خلاصہ یہ ہے:
ا.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ترتیب کے مطابق قرآن کریم لکھواتے تھے جو کہ ترتیب نزولی سے مختلف تھی.۲.حفاظ اسی ترتیب کے مطابق حفظ کرتے جس ترتیب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم لکھواتے اور اسی
ترتیب کے مطابق تلاوت کرتے.۳.نمازوں ، درسوں، خطبات، تقاریر اور مجالس وغیرہ میں قرآن کی سورتوں کی تلاوت موجودہ ترتیب کے
مطابق کی جاتی تھی.۴.ہر رمضان میں قرآن کریم کی دہرائی ہوتی اور آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آخری آنے والے
رمضان میں دومرتبہ ہوئی.یہ دہرائی اس ترتیب کے ساتھ ہوتی تھی.منازل کی تقسیم رسول کریم کے دور میں رانی تھی اور اس تقسیم میں سورتوں کی جو ترتیب تھی وہی ترتیب آج
بھی رائج ہے اور اس میں کسی زمانہ میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی.۶.حضرت ابوبکر کے دور خلافت میں جمع قرآن کے وقت امت کا ترتیب کے معاملہ میں کسی قسم کا کوئی
اختلاف سامنے نہیں آیا.ے.حضرت عثمان کے دورِ خلافت میں جمع قرآن کے وقت امت کا ترتیب کے معاملہ میں کسی قسم کا کوئی
اختلاف سامنے نہیں آیا.پس یہ سب امور اس بات پر دلیل ہیں کہ ترتیب سور نہ صرف رانی تھی بلکہ انتہائی واضح امر تھا جیسا کہ آج کل ہے.پس آیات کی طرح سورتوں کی دائگی ترتیب بھی تو قیفی ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے الہی
راہنمائی میں خود لگائی اور جس طرح امت نے اسے لگایا نہیں اسی طرح امت اسے بدل بھی نہیں سکتی.اب ذیل میں ان روایات کا تجزیہ کرتے ہیں جن سے یہ نتیجہ نکالا جاتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم
کی حیات مبارکہ میں سورتوں کی کوئی ترتیب تھی ہی نہیں یا جو ترتیب تھی وہ کبھی بعد میں بدل دی گئی اور صحابہؓ نے
قرآن کریم میں سورتوں کی ترتیب لگائی تھی.اس خلاف واقعہ خیال کے پیدا ہونے کی ایک بڑی وجہ وہ روایات ہیں جن میں ذکر ملتا ہے کہ حضرت ابوبکر
کا جمع کیا ہوا قرآن مجید غیر مجلد اور ان سلا تھا جس کے نتیجہ میں بعض لوگوں میں یہ غلط خیال بھی رواج پا گیا ہے کہ
Page 215
قرآن کریم میں تحریف کے الزامات کے جواب
199
قرآن کریم کی سورتوں میں کوئی ترتیب نہیں تھی ہاں ہر سورت کے اندر آیات باہم مرتب اور مر بوط تھیں.مثلاً
الاتقان میں حضرت ابو بکر صدیق کے متعلق علامہ سیوطی ایک یہ روایت درج کرتے ہیں:
" حضرت ابوبکر نے قرآن کو " صحائف میں جمع کرایا اور سورتوں کے اندر آیات کو اسی
ترتیب سے رکھا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے بتائی تھی بعد ازاں حضرت عثمان نے اس
کو مصحف واحد میں جمع کیا اور سورتوں
کو باہم ترتیب بھی دی.“
(الاتقان جزء اول نوع ثامن عشر: جمع القرآن و ترتيبه فصل سوم صفحه 58)
اس غلط خیال کی حمایت میں بخاری کی ایک روایت سے غلط طور پر تقویت حاصل کی گئی ہے.اس روایت
میں بھی حضرت ابو بکر کے جمع کردہ نسخہ کے لیے حف “ اور حضرت عثمان کے تیار کردہ نسخہ کے لیے
مصحف “ کا لفظ استعمال ہوا ہے.(بخاری کتاب فضائل القرآن باب جمع القرآن
اس کی شرح میں فتح الباری شرح البخاری میں لکھا ہے:.وو
ووو
66
صحف اور مُصْحَف “ میں فرق یہ ہے کہ وہ ان سلے اور اق جن میں حضرت ابو بکر
کے وقت قرآن جمع کیا گیا تھا اور جن میں سورتیں غیر مرتب اور منتشر تھیں اُن آن سلے اوراق کو
صُحُف“ کہتے ہیں.اس میں ہر سورۃ الگ طور پر تھی اور گوہر سورۃ میں آیات باہم ترتیب
سے تھیں مگر سورتیں خود ترتیب سے نہ تھیں.پھر جب ان کو جلد کیا گیا اور سورتوں کو بھی باہم
ترتیب دے دی گئی تو وہ مجلد شکل ”مُصْحَف “کہلاتی ہے.(حافظ ابن حجر العسقانی: فتح الباري شرح البخاری کتاب فضائل القرآن باب
جمع القرآن جلد 9صفحه 118)
66
پھر علامہ بدرالدین محمد بن عبداللہ الہ کشی نے ابوالحسین بن فارس کا یہ قول ان کی کتاب ” الْمَسَائِلِ الْخُمُس “
کے حوالہ سے درج کیا ہے:
جمع قرآن کا کام تین مرتبہ ہوا.نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں پھر عہد صدیقی
66
میں اور پھر تیسری مرتبہ عہد عثمانی میں ہوا جس میں سورتوں کو ترتیب دی گئی.“
(البرهان في علوم القرآن ، الجزء الاول صفحه 238 " نسخ القرآن في المصاحف
مذکورہ بالا رائے علامہ زرکشی کی نہیں ہے.آپ صرف ایک دوسری رائے کا ذکر کر رہے ہیں.آپ کی رائے
گزرچکی ہے کہ آپ کے نزدیک ترتیب سور تو قیفی ہے.مندرجہ بالا حوالہ جات سے معلوم ہوتا ہے کہ:.ا.حضرت ابو بکر نے قرآن کریم مکمل طور پر کاغذ پر لکھوایا،
Page 216
الذكر المحفوظ
200
۲.اس مجموعہ کو ایک جلد میں جمع نہیں کیا گیا تھا چنانچہ اس میں سورتوں کی کوئی ترتیب نہیں تھی.مگر مؤخر الذکر بات غلط ہے اور ایک غلط نہی کے نتیجہ میں راہ پاگئی ہے.اگر دیکھا جائے تو واضح طور پر معلوم ہوتا ہے
کہ حقیقت یہ ہے کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عثمان کے عہد خلافت میں قرآن کریم کی ترتیب کا مسئلہ تھا ہی نہیں بلکہ
اصل مسئلہ اختلاف قراءت کا خاتمہ تھا اور یہ ہم گزشتہ باب میں ثابت کر آئے ہیں.صاحب البرهان، علامہ الزرکشی مذکورہ بالا روایات درج کرنے کے بعد ان سے اختلاف کرتے ہوئے اپنا مسلک
یوں بیان کرتے ہیں:.یہ بات غلط ہے کہ قرآن مجید کو ایک جلد میں سب سے پہلے حضرت عثمان نے جمع کیا بلکہ اس
کام کا سہرا بھی حضرت ابوبکر کے سر ہے.“
(البرهان في علوم القرآن ، الجزء الاول صفحه 235 نسخ القرآن في المصاحف)
پھر اپنی تائید میں امام بیہقی کا یہ قول پیش کرتے ہیں:
ہم زید بن ثابت سے یہ روایت کر آئے ہیں کہ قرآن مجید کی ترتیب زمانہ نبوی میں ہوئی
اور اسے ایک جلد میں جمع کرنے کا کام حضرت ابوبکرؓ کے عہد میں ہوا اور حضرت عثمان کے وقت
میں اسے متعدد نسخوں میں نقل کیا گیا.“
(البرهان في علوم القرآن ، الجزء الاول صفحه 235 ” نسخ القرآن في المصاحف)
پھر ایک اور جگہ اپنا مؤقف ان الفاظ میں لکھتے ہیں:
صحابہ کا قرآن کریم ایک جگہ جمع کرنے کا سبب وہی ہے جو حدیث میں وارد ہوا ہے کہ
قرآن کھجور کی ٹہنی کے ڈنٹھلوں ، شانے کی ہڈیوں، پتھر کی باریک سلوں اور لوگوں کے سینوں میں
منتشر تھا.پھر حفاظ کرام کے کثرت سے وصال پا جانے کی وجہ سے یہ خوف پیدا ہو گیا تھا کہ مبادا
قرآن کا ایک حصہ ضائع ہو جائے.چنانچہ انہوں نے قرآن کو اسی ترتیب اور طریق سے جمع کیا
اور لکھا جیسا کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے سنا تھا اور اس میں انہوں نے اپنی
طرف سے کوئی تقدیم وتا خیر نہیں کی.(البرهان في علوم القرآن جزء اول صفحه 236 ” نسخ القرآن في المصاحف )
پھر ” البرھان میں حضرت علیؓ کا یہ قول درج ہے.رَحِمَهُ اللهُ أَبَا بَكْر هُوَ اَوَّلُ مَنْ جَمَعَ الْقُرْآنَ بَيْنَ لَوْحَيْنِ *
66
(بدرالدين الزركشی البرهان في علوم القرآن ، الجزء الاول صفحه 235)
یعنی اللہ تعالیٰ ابوبکر" پر رحم کرے کہ آپ وہ ہیں جنہوں نے قرآن کو ایک جلد کی
Page 217
قرآن کریم میں تحریف کے الزامات کے جواب
شکل میں جمع کیا.201
کتاب المصاحف میں بہت سی اسناد کے ساتھ حضرت علی کا یہ قول درج ہے کہ:
عن على قال اعظم الناس اجرا في المصاحف ابوبكر فانه اول من جمع
ابن ابی داؤد کتاب المصاحف الجزء الاول سفحه 5)
بين
اللوحين
قرآن کریم کے معاملہ میں حضرت ابو بکر کا اجر سب سے عظیم ہے کیونکہ انہوں نے سب
سے پہلے قرآن کریم کو مجلد شکل میں پیش فرمایا.الاتقان میں قاضی ابوبکر کا قول ان کی کتاب الانتصار کے حوالہ سے درج ہے کہ:
حضرت عثمان نے وہ کام نہیں کیا تھا جو حضرت ابوبکر نے کیا تھا اور حضرت ابوبکر نے یہ کام
کیا تھا کہ قرآن مجید کو بَینَ لَوْحَيْن ، یعنی ایک جلد میں جمع کیا تھا.(الاتقان في علوم القرآن الجزء الأوّل نوع الثامن عشر جمعه و ترتيبه صفحه 61)
مندرجہ بالا مستند روایات سے یہ حقیقت بپایہ ثبوت پہنچ جاتی ہے کہ حضرت ابو بکر کے دورِ خلافت میں
جمع قرآن کے وقت قرآن کریم کی سورتوں کی کوئی نئی ترتیب نہیں لگائی گئی بلکہ وہی ترتیب قائم رہی جو
رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی وحی کے مطابق لگائی تھی اور جو آپ کے عہد مبارک میں صحابہ میں
رائج اور مستعمل تھی.کتاب المصاحف میں ابن ابی داؤد یہ روایت درج کرتے ہیں کہ جمع حضرت ابو بکڑ نے کیا
اور حضرت عثمان کے بارہ میں لکھتے ہیں:
فوفق الله عثمان فنسخ تلك الصحف في المصاحف فبعث الله الى
المصار و ثبها في المسلمين:
ابن ابی داؤد: كتاب المصاحف الجزء الاول صفحه 23)
اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان کو یہ توفیق دی کہ حضرت ابوبکر کے جمع کیے ہوئے مصاحف کی
نقول کروا کر بلاد اسلامیہ میں پھیلادیں اور مسلمانوں میں رائج کردیں.حضرت الحاج حکیم مولانا نورالدین صاحب خلیفتہ امسیح الاوّل رضی اللہ عنہ اس بارہ میں فرماتے ہیں:.لوگ حضرت عثمان کو جامع القرآن بتاتے ہیں.یہ بات غلط ہے.صرف عثمان کے لفظ
کے ساتھ قافیہ ملایا ہے.ہاں شائع کنندہ قرآن اگر کہیں تو کسی حد تک بجا ہے.آپ کی خلافت
کے زمانہ میں اسلام دُور دُور تک پھیل گیا تھا.اس لیے آپ نے چند نسخه نقل کرا کر مکہ، مدینہ، شام
، بصرہ، کوفہ اور بلاد میں بھجوا دیئے تھے اور جمع تو اللہ تعالیٰ کی پسند کی ہوئی ترتیب کے ساتھ نبی
کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ہی فرمایا تھا اور اسی پسندیدہ ترتیب کے مطابق ہم تک پہنچایا
Page 218
الذكر المحفوظ
202
گیا.ہاں اس کا پڑھنا اور جمع کرنا ہم سب کے ذمہ ہے.“
(ضمیمہ اخبار بدر قادیان.14اپریل 1912ء بحوالہ حقائق الفرقان جلد 4 صفحہ 272)
حضرت خلیفہ المسیح الاول رضی اللہ عنہ کے اس فرمان سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ تحریری شکل میں
آنحضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم ہمیں قرآن کریم دے گئے تھے باقی ہر وہ شخص جو قرآن کریم کی خدمت کرتا ہے وہ
جمع قرآن میں شریک ہے اور اس طرح جمع قرآن کا فریضہ ساری امت مسلمہ سرانجام دے رہی ہے.یہ سلسلہ جاری
ہے اور تا قیامت جاری رہے گا.یہ بات بھی غور طلب ہے کہ اگر سورتوں کی ترتیب اللہ تعالیٰ کی لگوائی ہوئی نہ ہوتی بلکہ امت نے اپنی مرضی
سے لگائی ہوتی تو پھر قرین قیاس ہے کہ بعد میں کبھی ترتیب میں بہتری کی گنجائش نکل آتی اور جو شخص کسی ترتیب کو
زیادہ درست سمجھتا اسے اختیار کر لیتا.اس طرح گویا قرآن کریم کی ترتیب لگانے کی ہر کسی کو اجازت مل جاتی.مگر
آج تک ایسا نہ ہوا جو اس بات کا بین ثبوت ہے کہ قرآن کریم کی موجودہ ترتیب بھی خدا تعالیٰ کی نازل کردہ ہے
اور قرآن کریم کے الفاظ اور معانی کی طرح اس کی ترتیب کی حفاظت بھی خود خدا تعالیٰ فرمارہا ہے اور جس طرح
قرآن کریم میں اور کوئی تبدیلی ممکن نہیں اسی طرح اس کی ترتیب میں بھی کوئی تبدیلی ممکن نہیں.اگر یہ ترتیب خدا
کی لگائی گئی نہ ہوتی بلکہ ابو بکڑ نے لگوائی ہوتی تو پھر اب تک محفوظ نہ ہوتی اور مختلف ادوار میں اس کی مختلف ترتیبیں
لگانے کی کوشش ضرور کی جاتی.خصوصاً جبکہ مختلف ادوار میں ایسے مسلم اور غیر مسلم علما موجود رہے ہیں جن کا یہ خیال
تھا کہ ترتیب سور تو قیفی نہیں ہے.پس قرآن کریم کے الفاظ اور آیات کی حفاظت کی طرح اس کی ترتیب کی
حفاظت بھی اس کے تو قیفی ہونے کی ایک لطیف دلیل ہے.پھر یہ کہنا عقلاً بھی غلط ہے اور ہر گز قابل قبول نہیں کہ حضرت ابوبکر نے قرآن تحریر تو کروایا مگر اسے رسول
کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لگوائی ہوئی ترتیب کے مطابق ایک جلد میں جمع کر کے مکمل نہ کیا.ایک طرف یہ علماء کہتے
ہیں کہ حضرت ابوبکر نے اسی لیے قرآن کریم جمع کرنے کا حکم دیا تھا کہ کہیں قرآن کریم کی تحریرات ضائع نہ
ہو جائیں اور دوسری طرف آپ کے بارہ یہ موقف رکھنا کہ پھر ان اوراق کو پراگندہ چھوڑ دیا اور جلد نہ کروایا
سراسر نا انصافی ہے.نہ تو پہلے سے موجود تحریرات کو جلد کیا اور نہ ہی اس نے نسخہ کو جلد کیا تو پھر ان علماء کے نزدیک
آپ نے کام کیا کیا ؟ حضرت ابو بکر جیسے صاحب فراست و بصیرت نے اتنے عظیم الشان کام
کا بیڑہ اُٹھایا ہو اور
ایک زبر دست تحریک پر یہ سب شروع کیا ہو اور خاص نازک حالات میں اور ان کے نتیجہ میں ممکنہ ہولناک
مصائب کے پیش نظر کیا ہو اور اس یقین پر کیا ہو کہ حفاظت قرآن کے ضمن میں ایک بہت اہم قدم اٹھایا جارہا
ہے.پھر وہ کام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ دوم اور خاص مشیر نبوی کا ارفع و اعلیٰ مقام رکھنے والے
Page 219
قرآن کریم میں تحریف کے الزامات کے جواب
203
صاحب فراست حضرت عمر کی خاص نگرانی، اور کاتب رسول کے ہاتھوں اور تمام صحابہ رسول صلی اللہ علیہ والہ وسلم
کی عام نگرانی میں ہوا اور صحابہ بھی وہ جن پر لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاس (البقرة: 44) کی عظیم ذمہ داری
ڈالی گئی.کیا ایسے اہم اور نازک کام کو ان خدا داد بصیرت رکھنے والے اور دوراندیش عظیم لوگوں نے ادھورا ، تشنہ اور
مشتبہ چھوڑ دیا ہوگا ؟ نیز کیا ایسا ممکن ہے کہ پھر اس نامکمل کام کو حضرت عمر نے اپنے دورِ خلافت میں بھی مکمل نہ کیا؟
خصوصاً ایسے وقت اور پس منظر میں جب کہ اس ساری مہم کا مقصد ہی قرآن کو آخری کتابی شکل میں محفوظ کرنا تھا.ہرگز ایسا نہیں ! بلکہ انہوں نے اپنا فرض کمال امانت، دیانت اور کمال صحت کے ساتھ ادا کر دیا تھا اور یقیناً کر دیا تھا
اَللّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمُ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا وَ بَعْضٍ ثَانِ
اگر اس امر محال کو تسلیم کر بھی لیا جائے تو بھی یہ نتیجہ نہیں نکل سکتا کہ قرآن کریم کی سورتوں کی کوئی ترتیب نہیں
تھی.کیونکہ سورتوں کی ترتیب ہونے اور بہت سے دلائل ملتے ہیں.خصوصاً جبکہ یہ امر ثابت شدہ ہے کہ حفاظ موجود
تھے، قرآن کریم کی درس و تدریس جاری تھی، صحابہ اپنے اپنے طور پر کثرت سے قرآن کریم کا دور مکمل کیا کرتے
تھے.پھر رمضان میں سارے قرآن کی دہرائی ہوتی تھی اور یہ سب ایک ترتیب سے ہی تھا.پھر منازل
کی تقسیم سے
ایک خاص ترتیب کا علم ہوتا ہے جو صحابہ کرام میں آنحضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی رائج تھی.پس سورتوں
کی ترتیب تو اس دور میں ہر خاص و عام کے
علم میں تھی.اگر اس دور میں قرآنی مسودہ غیر مرتب شکل میں
رکھ بھی دیا جا تا تو یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کیونکہ ہر شخص جانتا تھا کہ قرآن کریم کی اصل ترتیب کیا ہے.حضرت ابوبکر کے جمع قرآن کا مقصد تو امت کی گواہی اکٹھی کرنا تھا کہ انہیں مکمل اطمینان ہے کہ یہ وہی قرآن
ہے جو تم آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ چکے ہو.ترتیب بدلنے پر امت مسلمہ نے یہ اعتراض کیوں نہ کیا کہ بیہودہ
قرآن نہیں ہے بلکہ اس کی ترتیب بدل دی گئی ہے اس لیے ہم گواہی نہیں دیں گے کہ یہ نسخہ بعینہ وہی ہے جو رسول
کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سپر د کیا تھا؟ پس اگر ترتیب نزول کے علاوہ پہلے سے کوئی ترتیب موجود نہ
ہوتی اور حضرت ابو بکر ترتیب لگوا رہے ہوتے تو ضرور اختلاف رائے کی وجہ سے جھگڑا کھڑا ہو جاتا.حضرت عثمان کے عہد خلافت میں امت مسلمہ میں جو اختلاف راہ پارہا تھا وہ ترتیب سور کا نہیں بلکہ مختلف قراء توں
کی وجہ سے تھا.پس آپ کے بارہ میں بھی یہ کہنا کہ اختلاف قراءت پر سورتوں کی نئی ترتیب قائم کر دی، سوال دیگر
جواب دیگر والی بات ہے.اس طرح تو بجائے اختلاف حل ہونے کے ایک نیا اختلاف پیدا ہو جاتا.یہ بات بھی ذہن نشین رہنی چاہیے کہ قرآن کریم کی ترتیب نزول
کبھی بھی مسلمانوں میں رائج نہیں رہی اور علمی
میدان میں محققین قرآنی معارف کو سمجھنے کے لیے تو اسے استعمال کرتے رہے ہیں لیکن قرآن کریم کی دائمی ترتیب وہی
ہے جو اللہ تعالی کی مقر فرمودہ ہے اور آنحضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے وصال سے پہلے صحابہ میں مکمل طور پر رائج اور محفوظ
Page 220
الذكر المحفوظ
204
شدہ تھی.جس کے بارہ میں کسی قسم کا کوئی خطرہ نہ تھا اور ترتیب نزول کا علم بھی ایسا تھا جوصرف صحابہ تک محدود تھا جو اسے
آگے منتقل کرنا اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے اور واقعی اگر صحابہ یہ کارنامہ سرانجام نہ دیتے تو قرآن کے کئی معارف جو ترتیب
نزول کی مدد سے سمجھنے آسان ہیں ہمشکل ہو جاتے.اللہ تعالیٰ اُن سب کو جزا دے کہ کس باریک بینی سے ایک ایک
قرآنی امانت کو ہم تک پہنچایا.یہ سب حفاظت قرآن کے بارہ میں الہی تقدیر کا ایک نمونہ اور صحابہ کی قرآن کریم سے بے
پناہ محبت اور اس امانت کی حفاظت کی ذمہ داری کا پوری شان کے ساتھ نبھانے کا زندہ ثبوت ہے.(رضی اللہ نھم )
خلاصه
مذکورہ بالا بحث سے یہ بات واضح ہو کر سامنے آتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ ہی کی
نگرانی میں قرآن کریم کی دائمی ترتیب لگائی گئی جو آج بھی بلا رد و بدل ہمارے سامنے موجود ہے.یہ ترتیب خود
خدا تعالیٰ نے لگوائی تھی اور یہ وہی ترتیب ہے جس کے مطابق آپ اور آپ کے مقرر کردہ اساتذہ ، صحابہ کو قرآن
کریم پڑھاتے اور سکھاتے تھے.اسی ترتیب کے مطابق قرآن کریم حفظ کیا جاتا تھا اور اسی ترتیب کے مطابق
نمازوں وغیرہ میں تلاوت کی جاتی تھی.رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی زندگی میں اس ترتیب سے قرآن کو
ایک جلد میں جمع کرنا ممکن نہیں تھا کیونکہ ہمہ وقت تازہ بتازہ وحی کا نزول ممکن تھا.مگر جب آپ کی وفات سے وحی
شریعت کا نزول بند ہو گیا تو صحابہ نے حضرت ابو بکر کی نگرانی میں قرآن کریم کو تمام تر احتیاطی تدابیر، اور حفاظت
کی جملہ شرائط پوری کرتے ہوئے اس فریضہ کو سر انجام دیا.تمام امت اس میں براہِ راست شریک تھی اور ہر
مسلمان پورے انشراح صدر کے ساتھ قرآن کریم کی جمع و تدوین پر متفق ہوتا چلا جار ہا تھا.پھر یہ کام مخالفین کی
آنکھوں کے سامنے ہو رہا تھا.یہ تدوین بائبل کی طرح بند کمروں میں منعقد کی جانے والی مجالس میں نہیں بلکہ عوام
الناس کے سامنے تمام تر ثبوتوں کے ساتھ کی جا رہی تھی.ایک ایک لفظ پر پوری امت کی گواہی ثبت ہورہی تھی.یوں گویا مسلمان اور غیر مسلم دونوں اس جمع و تدوین کے گواہ بنتے چلے جارہے تھے.حکم و عدل علیہ السلام کا ارشاد:
اس یقین محکم کی بنیاد حکم و عدل حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے اس قول فیصل پر ہے:
ترجمه (از عربی عبارت):.پھر اس کے بعد خلیفہ اول حضرت ابوبکر کھڑے ہوئے تا
جمیع سور قرآن کو اس ترتیب کے مطابق جمع کرنے کا اہتمام کریں جس ترتیب کو انہوں نے
آنحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے سنا تھا.“
(حمامة البشری، روحانی خزائن جلد 7 صفحہ 217)
Page 221
قرآن کریم میں تحریف کے الزامات کے جواب
205
پھر ابن وراق
کا یہ کہنا بھی جہالت کی حد ہے کہ " جس کسی نے بھی قرآن کریم جمع کیا ہے اس نے زیادہ لبی
سورتیں شروع میں رکھی ہیں.اس بات میں ایک ذرہ بھی شک نہیں اور یہ حقیقت بہت عام فہم تاریخی عقلی اور نقلی
دلائل سے ثابت شدہ اور نا قابل تردید ہے کہ جمع قرآن کا کام خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر نگرانی اور
آپ کے دور میں ہوا تھا.یہ کام اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں لیا تھا اور خود اپنی جناب سے اس کے سامان کیے
تھے.چنانچہ قرآن کریم کی ہر قسم کی ترتیب خدا تعالیٰ کی راہنمائی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم ہی نے لگائی
تھی.پس اس صورت میں تو وہ اعتراض بھی باقی رہتا ہی نہیں جس کی ابنِ وراق نے یہ جھوٹی بنیاد بنائی تھی کہ
قرآن جس نے بھی جمع کیا ہے اس ترتیب کے مطابق نہیں کیا جس کے مطابق کہا جاتا ہے کہ اللہ نے نازل کیا
ہے.ہم کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ ، جس نے قرآن نازل کیا ہے اس نے جمع کیا اور اُسی نے اس کی دائمی ترتیب،
نزول کی ترتیب سے ہٹ کر لگائی ہے.پس بشمول آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخص نے ترتیب نہیں بدلی بلکہ خود
خدا نے بدلی ہے.اس پر کون اعتراض کر سکتا ہے؟
جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ زیادہ لمبی سورتیں شروع میں رکھی ہیں.تو یہ بات بھی غلط ہے.یعنی جھوٹی
بنیاد بنا کر جو بات کی وہ بات بذات خود غلط ہے.سورتوں کی ترتیب ایسی نہیں ہے جیسا کہ بیان کر رہا ہے.سورتوں کی تریب کے بارہ میں ابن وراق ہی نہیں بلکہ اکثر مستشرقین بلاسوچے سمجھے ایک دوسرے کی تقلید میں یہ
کہ دیا کرتے ہیں اور کئی کورانہ تقلید کرنے والے مسلمان بھی اس غلطی کو دہرا دیتے ہیں.حضرت مرزا بشیر الدین
لمصل
محمود احمد صاحب خلیفہ المسیح الثانی اصلح الموعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں:
یہ دعویٰ ایک نہایت لغو اور حقیقت سے دُور دعوی ہے.کیونکہ (۱) قرآن کریم کی
سورتوں کی موجودہ ترتیب خود اس دعوی کو باطل کرتی ہے.پہلی سورۃ فاتحہ ہے جو نہایت
چھوٹی اور سات آیتوں کی سورۃ ہے.دوسری بقرۃ نہایت لمبی ہے.تیسری آل عمران ہے
جس کے ہیں رکوع ہیں لیکن چوتھی نساء کے چوبیں رکوع ہیں اسی طرح اگلی سورتوں میں بھی
کئی جگہ فرق ہے.پس یہ کہنا کہ لمبائی کے مطابق سورتوں کو آگے پیچھے رکھ دیا گیا ہے
درست نہیں.(۲) قرآن کا جمع کرنا کسی بندہ کا فعل نہیں بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ
وسلم کا بھی فعل نہیں.اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اِنَّ عَلَيْنَا جَمُعَهُ وَ
قُرْآنَة (القيامة رکوع ۱ ) [18] یعنی قرآن کریم کا جمع کرنا اور اس کا دُنیا میں پھیلانا یہ
دونوں کام میں خود کروں گا اور میرے خاص حکم اور نگرانی سے یہ کام ہوں گے.پس ایک
مسلمان کے نزدیک تو یہ انسانی کام ہو ہی نہیں سکتا اور غیر مسلموں کے لیے وہ جواب ہے جو
Page 222
الذكر المحفوظ
206
بیان ہو چکا.(۳) تیسرا جواب یہ ہے کہ سب سورتوں کے مضامین میں جو ترتیب
موجود ہے اگر صرف لمبائی اور اختصار پر انہیں آگے پیچھے رکھا گیا تھا تو پھر سورتوں کے
مضامین میں جوڑ اور اتصال کیوں کر پیدا ہو گیا.؟
( تفسیر کبیر جلد 1 صفحہ 52 تفسیر سورۃ الفاتحہ )
حضرت مرزا بشیر احمد صاحب اس بارہ میں فرماتے ہیں:
اکثر یورپین محققین یہ کہا کرتے ہیں کہ قرآنی سورتوں کو ان کی لمبائی کے لحاظ سے ترتیب
دیا گیا ہے.مگر یہ ایک سراسر بے بنیاد خیال ہے کیونکہ اول تو ہم اوپر ثابت کر چکے ہیں کہ جمع و
ترتیب کا کام خود آنحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے خدائی تفہیم کے مطابق سرانجام دیا تھا اور
آنحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم جیسے انسان کی طرف اس
قسم کا عبث فعل کبھی منسوب نہیں کیا
جاسکتا.ایسا فعل وہی شخص کر سکتا ہے جو عقل و خرد سے بالکل عاری ہو.نزول کی ترتیب کو محض اس
وجہ سے ترک کرنا کہ قرآنی سورتیں لمبے اور چھوٹے ہونے کے لحاظ سے ترتیب دی جاسکیں جس
میں کوئی بھی علمی فائدہ متصور نہیں ہے، ایک ایسا فعل ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی
ذات تو در کنار ایک معمولی عقل کا آدمی بھی اس کا مرتکب نہیں ہو سکتا تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ و
الہ وسلم کی ذات تو اس سے بہت ہی بالا اور ارفع ہے.دوسرے سورتوں کا وجود ہی جس کی وجہ سے
یہ خیال پیدا ہوا ہے کسی ترتیب کا نتیجہ ہے.کیونکہ قرآن شریف سورتوں کی صورت میں نازل نہیں
ہوا بلکہ آیات کی صورت میں بہت آہستہ آہستہ نازل ہوا ہے اور سورتیں آیات کے جمع ہونے سے
عالم وجود میں آئی ہیں.علاوہ ازیں یہ بات عملاً بھی بالکل غلط اور خلاف واقعہ ہے کہ قرآن میں
سورتوں کے لمبا چھوٹا ہونے کی ترتیب مد نظر رکھی گئی ہے اور قرآنی سورتوں کی آیات کی تعداد کا
ایک سرسری مطالعہ بھی اس کی تردید کے لیے کافی ہے کیونکہ بیسیوں مثالیں ایسی ہیں کہ بعض لبی
سورتیں ہیں جو پیچھے رکھی گئی ہیں اور بعض چھوٹی سورتیں ہیں جو پہلے آگئی ہیں اور نہ معلوم مغربی
محققین اس معاملہ میں اس قدر کوتاہ نظری اور فاش غلطی کے مرتکب کس طرح ہوئے ہیں.( سيرة خاتم النبین حصہ دوم زیر عنوان ترتیب قرآن صفحه 535)
اس اعتراض کے پیدا ہونے کی ایک وجہ قرآن مجید کے نزول کے حالات سے ناواقفیت بھی ہے.قرآن مجید
کے نزول کے دور میں تو کئی کئی سورتیں اکٹھی نازل ہوتی تھیں.ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ ایک سورۃ پہلے نازل ہونا
شروع ہوئی لیکن ایک دوسری سورۃ جو بعد میں نازل ہونا شروع ہوئی اس سے پہلے مکمل ہو گئی.پس کیسے فیصلہ کیا
جائے گا کہ کون سی سورۃ پہلی ہے اور کون سی بعد کی.ایک سورۃ جو پہلے نازل ہونا شروع ہوئی جو پہلی ہے یا جس کا
Page 223
قرآن کریم میں تحریف کے الزامات کے جواب
207
نزول پہلے مکمل ہوا وہ پہلی ہے.ہاں اس حد تک یہ بات درست ہے کہ بعض سورتیں بعض دوسری سورتوں سے
پہلے نازل ہونا شروع ہوئیں اور مکمل بھی پہلے ہوئیں.لیکن قرآن کریم میں وہ بعد میں نازل ہونے والی سورتوں
کے بعد درج ہیں لیکن یہ جائے اعتراض نہیں کیونکہ خود خدا تعالیٰ ، جس نے کہ قرآن نازل کیا ہے وہی اس کی دائمی
ترتیب لگانے والا ہے.قرآن کریم کی ترتیب نزولی کے بدلنے میں حکمت
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسی کیا ضرورت پیش آگئی تھی کہ قرآن کریم کی ترتیب نزولی کو بدلا جائے اور اس
بدلنے کا فائدہ کیا ہوا؟ یہ ایک معقول سوال لگتا ہے کہ مگر شائد اس سوال کی معقولیت کو محسوس کرتے ہوئے ابن
وراق نے یہ سوال اُٹھانا پسند نہیں کیا اور یہ حکمت جاننے کی کوشش نہیں کی.لیکن قرآن کریم کے اسلوب بیان اور
اندرونی ربط کے بارہ میں اندازہ کرنے کے لیے اس حکمت کا بیان کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے.ترتیب کے بارہ میں روایات اور تحقیقات پر نظر کرنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ
علیہ وسلم ہر آیت اور سورۃ کو اس کے نزول کے ساتھ ہی اس کے مقام پر لکھوا دیتے تھے اور یہ مقام وحی سے متعین
ہوتا تھا اس لیے اس کا کوئی ایسا قاعدہ نہیں تھا کہ جو آیت آج نازل ہورہی ہے وہ کل والی آیت کے بعد رکھی
جائے.یہ بھی نہیں تھا کہ نفسِ مضمون کے تعین سے کسی دوسری ہم مضمون آیت سے پہلے یا بعد میں رکھی جائے.یہ بھی نہیں تھا کہ نئی نازل ہونے والی آیت اپنی لمبائی وغیرہ کے لحاظ سے جگہ پاتی ہو.لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا
با قاعدہ ایک ترتیب سے رکھنا بتاتا ہے کہ ہر آیت کا ایک الہامی ربط اور مقام ہوتا تھا جس کی رو سے وہ آیت بالکل
اسی جگہ چسپاں ہوتی تھی.ممکن ہے سطحی نظر سے دیکھنے سے وہ ربط اور تسلسل نظر نہ آتا ہومگر جس طرح آنحضور صلی
الہ علیہ والہ وسلم آیات کو ان کی جگہوں پر رکھواتے تھے اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اس
کی کوئی نہ کوئی ترتیب ضرور
تھی وہ ترتیب کیا تھی؟ اس ضمن میں بحث آگے آئے گی.سر دست ترتیب نزول کو موجودہ ترتیب سے بدلنے کی
حکمت پر بات ہو رہی ہے.قرآن کریم کے نزول کے ذریعہ دنیا کو ایک بالکل نیا اور عالمی نظام دیا جار ہا تھا.چنانچہ اول المخاطب لوگوں
کے حالات کے مطابق اور ان کے روحانی، اخلاقی ، معاشرتی مسائل اور پیش آمدہ واقعات اور ضرورت زمانہ کی
مناسبت سے وحی قرآن کا نزول ہوتا رہا.ایک دین کو بالکل آغاز میں متعارف کرانے کے لیے جن امور کی
ضرورت پہلے ہو سکتی ہے وہ پہلے نازل کیے گئے اور جن کی ضرورت نسبتا بعد میں ہوتی ہے وہ بعد میں نازل کیے
گئے.لیکن دائمی ترتیب میں اس نزولی ترتیب کو بدل دیا گیا کیونکہ قرآن کریم کو مکمل کتابی صورت میں پیش کرنے
کے لیے بعد میں آنے والوں کے مختلف حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے مختلف ترتیب کی ضرورت تھی.چنانچہ نزول
Page 224
الذكر المحفوظ
208
کے ساتھ ساتھ قرآن کریم ایک ایسی ترتیب سے محفوظ کیا جارہا تھا جو آئندہ زمانہ کے لیے موزوں تھی اور ترتیب
نزول سے مختلف تھی.یہ ترتیب لگانا کسی انسان کے بس میں تھا بھی نہیں کیونکہ بفرض محال اگر کوئی انسان اپنے
زمانہ کی ضرورت کو مکمل طور پر سمجھ بھی لے تو بھی آئندہ زمانوں کی ضرورت کو کیسے سمجھ سکتا ہے؟ پس یہ امر
قرآن کریم کے زبر دست معجزہ ہونے اور اس کے منجانب اللہ ہونے کی ایک دلیل ہے نہ کہ جائے
اعتراض ! اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم کسی انسان کا کلام نہیں ہے بلکہ ایک عالم الغیب ہستی کا
کلام ہے.حضرت خلیفتہ اسیح الثانی اس بارہ میں وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں:
پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَ رَتَّلْنَهُ تَرْتِيلًا ہم نے اس قرآن
کی ترتیب بھی نہایت اعلیٰ درجہ
کی رکھی ہے.یعنی نزول قرآن تو اس رنگ میں ہوا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے
زمانہ کے لوگوں کے لیے ضروری تھا لیکن بعد کی دائی ترتیب ہم نے اور طرح رکھی ہے تا کہ آنے
والے لوگ اپنے حالات کے مطابق اس سے فائدہ اٹھا ئیں.یہ ترتیب بھی اپنی ذات میں اس
بات کا ثبوت ہے کہ یہ قرآن کسی انسان نے نہیں بنایا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے خود نازل کیا ہے.اگر اس کتاب کی تصنیف میں کسی انسان کا دخل ہوتا تو وہ اس کی ایک ہی ترتیب رکھتا اور جس قسم
کے حالات اُسے پیش آتے.اُن کے مطابق وہ ایک کتاب تصنیف کرتا چلا جاتا مگر قرآن کریم
چونکہ عالم الغیب خدا کی طرف سے نازل ہوا تھا اور قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے
ایک مستقل ہدایت نامہ تھا اس لیے اس نے اپنی حکمت کاملہ کے ماتحت اس کے نزول کی ترتیب
اور رنگ میں رکھی اور اس کی تحریر کی ترتیب اور رنگ میں رکھی.نزول کی ترتیب تو اس زمانہ کے
اولین مخاطبوں کے وساوس و شبہات کے ازالہ اور اُن کے مسائل کو حل کرنے کے لیے رکھی گئی اور
بعد کی ترتیب اُن لوگوں کے لیے رکھی گئی جنہوں نے مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہونے کی وجہ
سے مذہب سے بہت حد تک واقف ہونا تھا یا جن کے لیے مسلمانوں کی ایک قائم شدہ جماعت کو
دیکھتے ہوئے وہ مسائل کوئی اہمیت نہیں رکھتے تھے جن مسائل پر شروع میں بحث کرنا ضروری تھا.مثلاً تمام محدث اور مورخ اس بات پر متفق ہیں کہ پہلی آیت جو رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم پر
نازل ہوئی وہ اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِی خَلَق کی تھی.حالانکہ موجودہ قرآن میں وہ سب سے
آخری پارہ میں ہے اور آخری پارہ کے بھی آخری حصہ میں ہے.اب گجا سب سے پہلے نازل
ہونے والی آیت اور گجا قرآن کے سب سے آخری پارہ میں اور آخری پارہ کے بھی آخری حصہ
میں اس کا رکھا جانا یہ بتاتا ہے کہ الہی حکمت کے ماتحت قرآن کریم کی دوترتیبیں ضروری تھیں.
Page 225
قرآن کریم میں تحریف کے الزامات کے جواب
209
ایک ترتیب تو وہ تھی جو ابتدائی مسلمانوں کے لحاظ سے اُن کے مناسب حال
تھی اور ایک ترتیب وہ
تھی جو آئندہ آنے والے مسلمانوں کے لحاظ سے جب قرآن مکمل ہو چکا تھا مناسب حال
تھی.اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ میں صرف اقرا کہا.اقرأ الکتاب نہیں کہا کیونکہ جس وقت اللہ
تعالی نے اقرأ فرمایا اُس وقت کوئی کتاب موجود نہیں تھی مگر جب سورۃ بقرۃ نازل ہوئی تو اُس
وقت تک کتاب نازل ہو چکی تھی اور بہت سی سورتیں مکہ مکرمہ میں پوری مکمل ہو چکی تھیں...پس
اس وقت ذلِكَ الْكِتَابُ کہنا بالکل درست تھا اور لوگوں کو سمجھ آسکتا تھا.اس ترتیب کی دنیوی
مثال یوں سمجھ لو کہ جیسے کھانا پکانے کے لیے باورچی کام شروع کرتے ہیں تو بعض دفعہ کھانے کی
ترتیب کے لحاظ سے ایک چیز بعد میں آتی ہے لیکن پکانے کے لحاظ سے باورچی اس کو پہلے پکاتا
ہے اور کوئی چیز کھانے میں پہلے آتی ہے لیکن وہ اس کو بعد میں پکاتا ہے اور اگر کوئی اعتراض کرے
کہ یہ چیز جو پہلے کھائی تھی تم نے بعد میں کیوں پکائی تو وہ جواب دے گا کہ یہ کھانی بے شک پہلے
تھی لیکن اس کے پکانے میں پندرہ منٹ لگتے ہیں.اگر اسے پہلے ہی پکا لیا جاتا تو اس وقت تک
یہ خراب اور باسی ہو جاتی اور جو چیز بعد میں کھلائی تھی بے شک وہ کھانی بعد میں تھی مگر اس کے
پکانے میں اڑھائی تین گھنٹے لگتے ہیں.اگر اس کو پہلے نہ پکایا جاتا تو وہ بچی رہتی.پس اس کی
ترتیب حکمت کے ماتحت ہوتی ہے.پکانے کی اور ترتیب ہوتی ہے اور کھانے کی اور ترتیب ہوتی
ہے.جب وہ پکاتا ہے تو اس امر کو نہیں دیکھتا کہ پہلے کون سی چیز کھانی ہے بلکہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ
جلدی کون سی چیز پکے گی.جو جلدی پک جاتی ہے اُسے وہ بعد میں تیار کر لیتا ہے اور جو دیر میں
پکتی ہے اُسے وہ پہلے تیار کرنا شروع کرتا ہے.جو چیز دیر میں پکتی ہے اگر وہ اُسے دیر سے
چڑھائے گا تو کھاتے وقت وہ چیز کچھی ہوگی.پس وہ دیر سے پکنے والی چیز کو چولہے پر پہلے رکھ
لے گا خواہ وہ آخر میں کھائی جانے والی ہو اور جلدی پکنے والی چیز کو بعد میں تیار کر لے گا خواہ وہ پہلے
کھائی جانے والی ہو.اس مثال سے ظاہر ہے کہ بعض چیزوں کی استعمال میں ترتیب اور ہوتی
ہے اور ان کی تیاری میں اور ترتیب ہوتی ہے.یہی طریق دنیا کے ہر کام میں نظر آتا ہے.حکومتیں
فوجیں تیار کرتی ہیں، ملک کی تنظیم کرتی ہیں، لوگوں کو تعلیم دلاتی ہیں، اُن کو مختلف فنون سکھلاتی
ہیں تو بعض لوگ جنہوں نے پیچھے کام کرنا ہوتا ہے اُن کی تیاری پہلے شروع کر دیتے ہیں اور بعض
لوگ جنہوں نے پہلے کام کرنا ہوتا ہے اُن کی تیاری بعد میں ہوتی ہے.مثلاً کسی کام کی ٹریننگ چھ
ماہ میں مکمل ہو جاتی ہے اور کسی کام کی ٹریننگ میں چارسال صرف ہوتے ہیں.اب خواہ ایک ہی
Page 226
الذكر المحفوظ
210
وقت میں کام شروع ہونے والے ہوں تب بھی چار سال والے کی ٹریننگ پہلے رکھی جائے گی اور
چھ ماہ والے کی بعد میں یہی قرآن کریم کی ترتیب کا حال ہے.قرآن کریم میں جو مضامین
اُس وقت کے لحاظ سے ضروری تھے جب وہ نازل ہو رہا تھا اُن کو خدا تعالیٰ نے پہلے رکھا کیوں کہ
اس وقت قرآن کریم ابھی اپنی مکمل صورت میں اُن کے سامنے نہیں تھا.انہیں کچھ معلوم نہیں تھا
کہ قرآن کیا ہوتا ہے، اسلام کیا ہوتا ہے، رسول کیا ہوتا ہے، وحی کیا ہوتی ہے، الہام کیا ہوتا ہے،
خدا تعالیٰ سے تعلق کیا ہوتا ہے.بلکہ انہیں یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ خدا کیا ہوتا ہے.اس لیے اُس وقت
پہلے ایسے مسائل بیان کیے گئے جو بنیادی حیثیت رکھتے تھے مگر جب وہ مسائل زیر بحث آگئے اور
پندرہ بیس سال تک وہ لوگ قرآن کریم کی آیات اور اُس کی تعلیم سنتے رہے تو اُس کے بعد اُن
کے ہاں جو اولاد پیدا ہوئی اُس نے اپنے ماں باپ سے یہ باتیں سنی شروع کر دیں اور بچپن سے
ہی اُس کے کانوں میں یہ ڈالا جانے لگا کہ خدا کیا ہوتا ہے، رسول کیا ہوتا ہے، الہام کیا ہوتا ہے،
اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کو خدا نے کیوں مبعوث فرمایا.پس
جب وہ بڑے ہوئے تو اُن کی ذہنیت اور قسم کی تھی.قرآن جب نازل ہوا تو اُس وقت قرآن کریم
کی بہت سی باتیں لوگوں کے لیے بالکل نئی تھیں.لیکن آئندہ اولاد کے لیے وہ باتیں پرانی ہو چکی
تھیں.غرض ترتیب قرآن نہایت اہم حکمتوں پر مبنی ہے نزول کی ترتیب اُن لوگوں کے مطابق
تھی جو اُس زمانہ میں تھے اور موجودہ ترتیب آئندہ آنے والی نسلوں کی ضرورت کے مطابق ہے
اور یہ اس کلام کے منجانب اللہ ہونے کا ایک بڑا بھاری ثبوت ہے.( تفسیر کبیر زیر آیت الفرقان : 23 جلد 4 صفحہ 490 تا492)
حضرت مرزا بشیر احمد صاحب ترتیب نزولی اور دائگی تریب میں فرق کی حکمت کے بارہ میں فرماتے ہیں:
یہ اختلاف دو اصول کے ماتحت ہے:
اول تو بوجہ اس کے کہ صحابہ کی جماعت وہ پہلی جماعت تھی جو اسلامی شریعت کے مطابق قائم
ہوئی اور اس سے پہلے کوئی جماعت اسلامی شریعت کی حامل نہیں تھی اور نہ ہی دُنیا میں اسلامی
شریعت کا وجود تھا اور قرآن کے ذریعہ سے پہلے طریق و تمدن کو مٹا کر ایک بالکل ہی نئے طریق و
تمدن کی بنیاد پڑنی تھی اس لیے ضروری تھا کہ اس وقت کے لوگوں کے سامنے ان کی ذہنیت اور
ماحول کے مناسب حال قرآنی احکامات کا نزول ہوتا تا کہ وہ اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو
بدلنے اور نئی تعلیم کو اپنے اندر جذب کرنے میں آسانی پاتے اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے بہترین
Page 227
قرآن کریم میں تحریف کے الزامات کے جواب
211
صورت یہ تھی کہ سب سے پہلے اس قسم کی آیات کا نزول ہوتا جن میں صرف عقیدہ کی درستی مدنظر
ہے اور مشرکانہ خیالات کو مٹا کر توحید کو قائم کیا گیا ہے اور اس کے بعد آہستہ آہستہ اسلامی
طریق عبادات اور اسلامی طریق معاملات اور اسلامی طریق تمدن اور اسلامی طریق سیاست
کے متعلق اوامر و نواہی نازل ہوتے.چنانچہ ایسا ہی کیا گیا.(بخاری کتاب فضائل القرآن باب
تالیف القرآن) لیکن جب ایک جماعت اسلام شریعت تیار ہوگئی تو اب اس تخم یا نیو کیس کی آئندہ
ترقی کے لیے وہ ابتدائی ترتیب نزول غیر طبعی اور ناموزوں تھی اس لیے اسے بدل کر وہ ترتیب
دے دی گئی جو اس کے لیے مناسب تھی.چنانچہ قرآن شریف کی موجودہ ترتیب بالکل اسی
اصول کے ماتحت ہے جو ایک تیار شدہ جماعت کے استحکام اس کے پھیلاؤ اور ترقی کے لیے
موزوں ترین ہے.دوسرا اصول نزول کی ترتیب کو بدل کر دوسری ترتیب کے اختیار کرنے میں یہ مدنظر تھا کہ
نزول کی ترتیب زیادہ تر ان حالات کے مطابق چلتی تھی جو آنحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم اور
آپ کے صحابہ کو پیش آتے تھے.مثلاً چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی کی زندگی میں ابھی
کفار پر اتمام حجت ہو رہا تھا اور مسلمانوں کو صبر و شکیب کے سانچے میں ڈھال کر نکالنا مقصود تھا.اس لیے مکی آیات میں جہاد کی تعلیم نہیں دی گئی بلکہ صبر و برداشت کی تعلیم پر زور ہے.لیکن جب
اتمام حجت ہو چکا اور صحابہ (رضوان اللہ علیہم اجمعین ) بھی صبر و برداشت کے سانچے میں ڈھل
چکے اور کفار کے مظالم سے مسلمانوں کو اپنا وطن تک چھوڑنا پڑا اور ظالم کی سزا کا وقت آگیا تو اُس
وقت جہاد کی آیات نازل ہوئیں اسی طرح مکہ میں چونکہ مسلمانوں کی کوئی جماعت بصورت
جمیعت نہیں تھی اور کفار کے مظالم نے انہیں بالکل منتشر کر رکھا تھا یعنی ان کی کوئی اجتماعی زندگی
نہیں تھی اس لیے مکہ میں اسلامی طریق تمدن و معاملات کے متعلق آیات نازل نہیں ہوئیں لیکن
جب مدینہ میں مسلمانوں کو ایک اجتماعی زندگی نصیب ہوئی تو اس کے مناسب حال آیات کا
نزول ہوا اگر اس نزول میں حالات کی مناسبت اور مطابقت کوملحوظ نہ رکھا جاتا تو یقیناً ابتدائی
مسلمانوں کے لیے نئی شریعت کو اپنے اندر جذب کرنا اور اس پر صحیح طور پر عامل ہونا سخت مشکل
ہو جاتا.لہذا قرآن کے نزول کو حتی الوسع حالات پیش آمدہ کے ساتھ ساتھ چلایا گیا تھا تا کہ اس
کی تعلیم صحابہ میں جذب ہوتی جاوے، لیکن جب سب نزول ہو چکا اور ایک جماعت قرآنی
شریعت کی حامل وجود میں آگئی تو پھر اس ترتیب کو قائم رکھنا ضروری نہ تھا بلکہ پھر اس بات کی ضرورت
Page 228
الذكر المحفوظ
212
تھی کہ آئندہ کی مستقل ضروریات کے مطابق اُسے ترتیب دی جاوے.چنانچہ ایسا ہی کیا گیا.(سيرة خاتم النبین حصہ دوم زیر عنوان ترتیب قرآن صفحه 536)
اس ضمن میں یہ بھی ذہن نشین رہنا چاہیے کہ قرآن کی ترتیب حفاظت قرآن کی خاطر حکیم خدا کی طرف سے
اختیار کیا گیا ایک غیر معمولی اور پُر حکمت طریق تھا.باوجود یکہ قرآن کریم کی حفاظت کا اتنا غیر معمولی انتظام
تھا پھر بھی یہ طریق اختیار کر کے اسے محفوظ تر بنادیا گیا.اس حقیقت کے ساتھ کہ قرآن
انتہائی معمولی رفتار سے اور
آہستگی کے ساتھ نازل ہور ہا تھا پھر بھی خدا تعالیٰ نے اس کو ذہنوں میں راسخ کرنے اور صحابہ کو اس کے معانی اور
مفاہیم از بر کروانے کے لیے اور اُس کی ہر آیت کو مستند ترین بنانے اور ہر ایک آیت کے وسیع مضامین سمجھانے کا
یہ انتظام کیا کہ اسے اس زمانہ کے پیش آمدہ حالات و واقعات کے ساتھ اس طرح ہم آہنگ کر کے پیش کیا کہ
ناممکن تھا کہ کوئی آیت نازل ہوتی اور صحابہ اس کے مضامین کو نہ سمجھتے.ہر آیت ایک لڑی میں پروئی ہوئی اور ایک
گلدستے میں شامل کیا جانے والا پھول بنتی ہوئی اور ساتھ ساتھ تاریخ کا حصہ بنتی ہوئی نازل ہورہی تھی.گویا
قرآن کریم کی ہر آیت کے سمجھانے کا خدا تعالیٰ نے یہ انتظام فرمایا کہ نازل تو قرآن نے بہر حال ہونا تھا لیکن
لوگوں کو سمجھانے کی خاطر کسی نا کسی واقعہ یا مختلف واقعات کے ساتھ ملا کر آیت نازل کی جاتی تھی اس لیے آج
کثرت کے ساتھ مختلف آیات کے مواقع النزول روایات میں ملتے ہیں.یوں قرآن کریم کا ہر ایک لفظ تاریخ کا
ایک نا قابل تردید اور مستند ترین حصہ بھی بن رہا تھا اور اس کے مضامین روز مرہ حالات و واقعات کے ساتھ ہم
آہنگ ہونے کی وجہ سے آسانی کے ساتھ ذہنوں میں راسخ ہورہے تھے اور ساتھ ساتھ یہ کلام اپنی ظاہری صورت
میں حفظ کے ذریعہ سینوں میں محفوظ ہور ہا تھا.چنانچہ آج کے ترقی یافتہ دور میں علمی دُنیا نے جو طریقہ تدریس اپنایا
ہے اللہ تعالیٰ نے پندرہ سو سال قبل قرآن کریم اس طریقہ کی انتہائی ترقی یافتہ شکل کے مطابق سکھایا جو ہر لحاظ سے
کامل تھی.آج کسی بھی اچھے تدریسی ادارہ میں جائیں وہاں صرف تھیوری پر انحصار نہیں کیا جاتا بلکہ ساتھ ساتھ
پریکٹیکل بھی کروائے جاتے ہیں.دیکھا جائے تو وہ پریکٹیکل بھی ایک مصنوعی ماحول پیدا کر کے کروائے جاتے
ہیں جو کہ عملی زندگی کے فوری اور ہنگامی حالات سے سو فیصد مطابق بھی نہیں ہوتے.پس جب لاکھوں کروڑوں
روپیہ خرچ کر کے مصنوعی ماحول بنا کر تھیوری کو از بر کروانے کا انتظام کیا جاتا ہے تو پھر قرآن کریم کی حفاظت کے
اس طریقہ پر کیوں اعتراض کیا جائے جو قطعاً مصنوعی نہیں جس میں تصنع نام کو نہیں اور جو حقیقی زندگی کے عین
مطابق بلکہ حقیقی زندگی کا حصہ ہے.یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو بند لیبارٹریوں میں نہیں بلکہ مخالفین کی آنکھوں
کے سامنے معرض وجود میں آئی.قرآن کریم کی ہر آیت کا نزول مومنین اور مخالفین کی نظروں کے سامنے اعلانیہ
طور پر ہورہا تھا اور انہیں پورا پورا موقع دیا جار ہا تھا کہ کسی بھی قسم کا اعتراض ہو تو پیش کریں.پھر نزول کی رفتار اتنی
Page 229
قرآن کریم میں تحریف کے الزامات کے جواب
213
معمولی تھی کہ مخالفین کو پوری پوری مہلت حاصل تھی کہ نئی آیات نازل ہونے سے پہلے سابقہ نازل شدہ آیات کے
بارہ میں مکمل تحقیق کرلیں اور ان کی خاموشی اس بات کی شہادت تھی کہ قرآن مذہبی کتاب ہونے کے ساتھ ساتھ
اپنے زمانہ کی مستند ترین تاریخ بھی ہے.چنانچہ زمانہ حال کے مستشرقین کا بھی اس پر اتفاق ہے کہ قرآن اپنے
زمانہ کے بارہ میں جو بات کرتا ہے وہ لازماً درست ہے کیوں کہ قرآن کریم تو سچا ہونے کا دعویدار ہے پس ہو نہیں
سکتا کہ مخالفین کے سامنے کوئی غلط اور خلاف واقعہ بات بیان کرے اور ہمعصر مخالفین خاموش رہیں.اس پر
اعتراض تو لاز ما ایک جاہل زبان ہی کر سکتی ہے یا پھر اس اعتراض کی بنیاد مذہبی تعصب اور دشمنی ہوگی اس سے
زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں.پس آنحضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا ان آیات کو ترتیب نزول سے ہٹ کر ایک
مختلف ترتیب پر لکھوانے سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ترتیب نزول کا تعلق صرف نزول کے دور سے ہے.قرآن کریم تحریر اور حفظ اسی ترتیب سے کیا گیا تھا جو دائمی تھی اور آج بھی وہی ترتیب ہے اور یہ ترتیب خدا تعالیٰ کی
راہنمائی میں آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر نگرائی ہی لگوائی گئی تھی.یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب قرآن کریم کی اصل ترتیب قائم نہیں رکھی گئی بلکہ آئندہ زمانہ کی
ضروریات کے مطابق کر دی گئی تو پھر اس کی عبارت سے وہ حسن معدوم ہو گیا ہوگا جو کہ ایک با ربط اور مربوط کلام
کا خاصہ ہوتا ہے.اس سوال کے جواب میں پہلے تو ہم گزشتہ اوراق میں بیان شدہ اس حقیقت کی طرف توجہ مبذول کراتے ہیں
کہ قرآن کریم کی موجودہ ترتیب خدا تعالیٰ ہی کی قائم فرمودہ ہے.پس اپنے تمام تر کاموں میں اعلیٰ درجہ کا حسن
اور خوبصورتی اور توازن قائم رکھنے والی ہستی نے اپنے کلام میں بھی اس خصوصیت کو بدرجہ اتم بھر دیا ہے.جس کا ہر
زمانہ کے عربی زبان کے اہل کمال اقرار کرتے آئے ہیں.قرآن کریم کا حسن بیان
اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اعلیٰ وارفع اُسلوب بیان کے لیے حسن کا لفظ اختیار کیا ہے اور صرف یہی نہیں
کہ قرآن کریم نے اپنے کلام کو صرف حسین کہا ہے بلکہ سب سے زیادہ حسین کہا ہے.اللہ تعالیٰ قرآن کریم
میں فرماتا ہے:
اللهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتبًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِي (الزمر:24)
یعنی اللہ نے بہترین بیان ایک ملتی جلتی ( اور ) بار بار دہرائی جانے والی کتاب کی صورت
میں اتارا ہے.
Page 230
الذكر المحفوظ
214
بلکہ کلام سے پہلے کلام کرنے والے یعنی اپنی ذات کو حسن کی تمام تجلیات کا خالق اور مجسم حسن قرار دیا ہے.فرمایا:
اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى :(طه: 9) وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ
بها (الاعراف: 181) اور اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام تخلیق کو حسین قرار دیا ہے.فرمایا.الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ
خَلْقَهُ (السجدہ : 32) اور فرمایا: فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ (المؤمن :15) اور انسان کو خصوصیت
سے حسین کہا ہے.فرمایا: وَ صَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمُ (المؤمن:40) اور پھر فرمانِ عام ہے کہ زندگی کے
ہر شعبے میں حسن کو اختیار کرو.فرمایا: إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِين (البقرہ: 196) اور خاص طور پر اپنے قول کو
حسین بناؤ.فرمایا: وَقُلْ لِعِبَادِى يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَن بنی اسرائیل: 18) اور فرمایا: قُولُوا لِلنَّاسِ
حُسْنًا (البقره: 84)
”ادب“ ایک بہت مختلف المعانی لفظ ہے اس لیے قرآن شریف کی فصاحت و بلاغت سے بعید تھا کہ وہ ایک
مخصوص معانی کے اظہار کے لیے ایک پراگندہ خیال لفظ کو اختیار فرماتا جس کے حقیقی اور مجازی معنوں میں
اختلاف ہو.اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے ادب پاروں کو ”ادب“ کا نام نہیں دیا بلکہ اس بہت بہتر معانی
کے حامل لفظ کو جو کہ در حقیقت ادب کی جان بھی ہے، اختیار فرمایا ہے.اللہ تعالیٰ نے اپنے فرمودات کو احسن
الحدیث اور احسن القصص کہا ہے.یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی عظمت اورشان ہے کہ اس نے ایسے لفظ کو قبول نہیں کیا
جو اپنے معانی اور مطالب کے اظہار میں ایسا اختلاف اور وسعت رکھتا ہو کہ اس سے نفسِ مضمون کا ایک مستقل
رشتہ قائم نہ ہو سکے.حقیقت تو یہ ہے کہ قرآن کریم لفظ حسن اور اس کے مشتقات سے بھرا پڑا ہے.یہی اس کی شان اور منصب
ہے کیونکہ جس ہستی کی طرف وہ بلاتا ہے وہ حقیقی معنوں میں حسن اول اور حسن آخر ہے اور قرآن اس حسن ازل اور
لم یزل کی بجلی ہے.قرآن کریم کے معجزانہ حسن بیان کے بارہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:
عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الْآيَاتُ
خَزَرَاتٌ مَنْظُومَاتٌ فِي سِلْكٍ
(مسند احمد مسند المكثرين من الصحابه مسند عبد الله بن عمرو بن العاص)
یعنی آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیات ایک لڑی میں پروئے ہوئے موتیوں کی طرح ہیں.حضرت مسیح موعود علیہ السلام قرآن کریم کے حسنِ بیان کے بارہ میں فرماتے ہیں:
ظاہری صورت پر نظر ڈال کر دیکھو کہ کیسی رنگینی عبارت اور خوش بیانی اور جودت الفاظ اور
کلام میں کمال سلاست اور نرمی اور روانگی اور آب و تاب اور لطافت و غیرہ لوازم حسن کلام اپنا
Page 231
قرآن کریم میں تحریف کے الزامات کے جواب
215
کامل جلوہ دکھا رہے ہیں.ایسا جلوہ کہ جس پر زیادت متصور نہیں.اور وحشت کلمات اور تعقید
ترکیبات سے بکلی سالم اور بری ہے.ہر یک فقرہ اس کا نہایت فصیح اور بلیغ ہے اور ہر یک
ترکیب اس کی اپنے اپنے موقعہ پر واقعہ ہے اور ہر یک قسم کا التزام جس سے حسن کلام بڑھتا ہے
اور لطافت عبارت کھلتی ہے.سب اس میں پایا جاتا ہے.اور جس قدر حسن تقریر کے لئے
بلاغت اور خوش بیانی کا اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ ذہن میں آ سکتا ہے وہ کامل طور پر اس میں موجود اور
مشہور ہے.اور جس قدر مطلب کے دل نشین کرنے کے لئے حسن بیان درکار ہے وہ سب اس
میں مہیا اور موجود ہے اور باوجود اس بلاغت معانی اور التزام کمالیت حسن بیان کے صدق اور
راستی کی خوشبو سے بھرا ہوا ہے.کوئی مبالغہ ایسا نہیں جس میں جھوٹ کی ذرا آمیزش ہو.کوئی
رنگینی عبارت اس قسم کی نہیں جس میں شاعروں کی طرح جھوٹ اور ہنرل اور فضول گوئی کی
نجاست اور بد بو سے مدد لی گئی ہو.پس جیسے شاعروں کا کلام جھوٹ اور ہنرل اور فضول گوئی کی
بد بو سے بھرا ہوا ہوتا ہے.یہ کلام صداقت اور راستی کی لطیف خوشبو سے بھرا ہوا ہے.اور پھر اس
خوشبو کے ساتھ خوش بیانی اور جودت الفاظ اور رنگینی اور صفائی عبارت کو ایسا جمع کیا گیا ہے کہ
جیسے گلاب کے پھول میں خوشبو کے ساتھ اس کی خوش رنگی اور صفائی بھی جمع ہوتی ہے.“
(براہین احمدیہ چہار صص حاشیہ نمبر گیارہ روحانی خزائن جلد اصفحہ 397,398 ایڈیشن اول صفحہ 334 )
ایک دوسری جگہ فرمایا:
اس کی عبارت میں ایسی رنگینی اور آب و تاب اور نزاکت و لطافت و ملا سمیت اور بلاغت اور
شیرینی اور روانگی اور حسنِ بیان اور حسن ترتیب پایا جاتا ہے کہ ان معانی کو اس سے بہتر یا اس سے
مساوی کسی دوسری فصیح عبارت میں ادا کرنا ممکن نہیں اور اگر تمام دنیا کے انشا پرداز اور شاعر متفق ہوکر
یہ چاہیں کہ اسی مضمون کو لے کر اپنے طور سے کسی دوسری فصیح عبارت میں لکھیں کہ جو سورۃ فاتحہ کی
عبارت سے مساوی یا اس سے بہتر ہو.تو یہ بات بالکل محال اور ممتنع ہے کہ ایسی عبارت
لکھ سکیں.کیونکہ تیرہ سو برس سے قرآن شریف تمام دنیا کے سامنے اپنی بے نظیری کا دعویٰ پیش کر رہا ہے.اگر
ممکن ہوتا تو البستہ کوئی مخالف اس کا معارضہ کر کے دکھلاتا.حالانکہ ایسے دعوے کے معارضہ نہ کرنے
میں تمام مخالفین کی رسوائی اور ذلت اور قرآن شریف کی شوکت اور عزت ثابت ہوتی ہے.(براہین احمدیہ چہار حصص حاشیہ نمبر گیارہ روحانی خزائن جلد اصفحہ 404 ایڈیشن اول صفحہ 339)
قرآن کریم کے بارہ میں ہر زمانہ میں اہل علم بلاتمیز عقیدہ و مذہب یہ گواہیاں دیتے آئے ہیں کہ اس جیسی اعلیٰ
درجہ کی ادبی خصوصیات رکھنے والی کتاب اہل زبان عربوں نے نہ پہلے کبھی دیکھی اور نہ آج تک اس کے مقابل پر
Page 232
الذكر المحفوظ
216
کوئی کتاب بنا سکے.بہت سے عربی دانوں نے بڑے بڑے پائے کی کتب لکھی ہیں مگر کبھی یہ دعوی نہیں کیا کہ ان
کی کتاب عربی ادب کے حسن کے کسی بھی شعبے میں قرآن کریم سے آگے نکل گئی ہے.بلکہ عربی زبان کے ماہرین
فصاحت و بلاغت کے میدان میں قرآن کریم کو قاضی قرار دیتے اور حسنِ کلام کی اعلیٰ ترین مثال کے طور پر
قرآن کریم کو ہی پیش کرتے آئے ہیں.عرب کا مشہور زمانہ شاعر لبید بن ربیعہ عامری نے جس کی شاعری کا شمار بلند ترین عربی ادب پاروں
میں ہوتا تھا اور جس کا قصیدہ سبعہ معلقات میں سے ایک تھا ، قرآن کریم کی اعلیٰ وارفع فصاحت اور بلاغت کا اعتراف
کرتے ہوئے کہ اس درجہ بلند پایہ کلام انسانی نہیں ہوسکتا اسلام قبول کرلیا تھا اور قرآن کریم کے انسانی طاقت
سے بالا اور الہبی کلام ہونے کی حقیقت پر اپنے ایمان کی پختگی کا اظہار اس طرح کیا کہ شعر کہنا چھوڑ دیا.حضرت عمرؓ
اعلیٰ ادبی ذوق رکھنے والے صاحب علم و فضل شخص تھے.لبیڈ کے اسلام قبول کرنے کے بعد کا واقعہ ہے کہ ایک
مرتبہ حضرت عمر نے لبیڈ سے شعر سنانے کی فرمائش کی.لبید نے جواب میں سورۃ البقرۃ کی تلاوت شروع کر دی.حضرت عمر کہنے لگے کہ جناب میں نے آپ سے اپنے شعر سنانے کو کہا ہے.اس پر لبید کہنے لگے کہ مـــا کـنــت
اقول بيتا من الشعر بعد ان علمنى الله البقرة و ال عمران یعنی جب اللہ تعالیٰ نے مجھے سورۃ البقرۃ اور ال
عمران سکھا دی ہیں تو اب کس طرح ممکن ہے کہ اس کے بعد میں ایک شعر بھی کہوں.حضرت عمر رضی اللہ عنہ کولبید کا
یہ جواب
اتنا پسند آیا کہ انہوں نے اُن کا وظیفہ دو ہزار درہم سالانہ سے بڑھا کر اڑھائی ہزار درہم سالانہ کر دیا.(اسد الغابہ جلد چہارم حالات لبید بن ربیعہ صفحہ 262 )
عربی کلاسیکی ادب سے واقف ہر شخص جانتا ہے کہ ادب عربی میں لبید بن ربیعہ ایک نمایاں اور بلند مقام کے
حامل ہیں.وہ اس درجہ کے شاعر تھے کہ اُن کا کلام اسلام کے فتح کے دور سے پہلے تک کعبہ میں آویزاں ان
ادب پاروں میں شامل تھا جو بہترین عربی شاعری کے نمونہ کے طور پر دیوار کعبہ پر سجائے گئے تھے.ادبی رفعتوں
کو چھونے والا دیانت دار انسان لبید قرآن کریم کے سحر انگیز حسن بیان کے اعتراف میں یہ قسم کھاتا ہے کہ اب
وہ تاحیات شعر نہیں کہے گا.کیونکہ قرآن کریم میں عربی زبان اپنے حسن کے معراج کو پہنچ گئی ہے اور اس کے بعد
کوئی کلام ایسا ہو ہی نہیں سکتا جو اس سے بڑھ جائے.طفیل بن عمرو دوسی ، یمن کے نواح میں رہنے والا معزز اور سحر بیان فصیح و بلیغ یمنی شاعر اپنے ادبی
کمالات، اثر ورسوخ ، دولت اور عزت و وجاہت کی وجہ سے امر اور ؤ سا میں شمار ہوتا تھا، خانہ کعبہ میں رسول کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں مشغول دیکھتا ہے.تجس پر آپ کے قریب ہوتا ہے اور جب تلاوت کی آواز کانوں
میں پڑتی ہے تو حسن بیان دیکھ کر قرآن کے کلام الہی ہونے کا قائل ہو جاتا ہے کہ اس شان کا کلام بنانا انسانی
طاقت سے بالا ہے اور مسلمان ہو جاتا ہے.(اسد الغابہ جلد چهارم حالات طفیل بن دوسی)
Page 233
قرآن کریم میں تحریف کے الزامات کے جواب
217
ضمار از دی ،سارے عرب میں اپنی سحر بیانی کی وجہ سے مشہور ، آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے
کلام کی سحر انگیزی کا سُن کر کمال تکبر اور شیخی سے مقابلہ کرنے کے لیے روبرو آتا ہے اور چند آیات کی تلاوت سُن
کر الہی کلام کے مقابل پر اپنی عاجزی اور اپنے کلام کے بے حیثیت ہونے کا اقرار کرتا ہے.(اسد الغابہ جلد
چہارم حالات ضمار از دی)
جبیر بن مطعم جب آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کرتے ہوئے سنتے ہیں تو کیفیت
ہی عجیب ہو جاتی ہے گویا دل خدائے واحد کی طرف اُڑتا چلا جارہا ہے.( بخاری کتاب التفسیر تفسیر سورۃ الطور )
ولید بن مغیرہ نے جب قرآن کریم سُنا تو کہنے لگے کہ خدا کی قسم ! اس کلام میں عجیب کشش اور شیرینی ہے اور آپ
پر رقت طاری ہوگئی.ابو جہل کو جب معلوم ہوتا کہ تلاوت قرآن کریم سُن کر ولید مسلمان ہو رہے ہیں تو سمجھانے
کے لیے آتا ہے.آپ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم ! محمد ( ﷺ ) جو کلام پڑھتے ہیں وہ شعر ہرگز نہیں کیونکہ میں شعر و
سخن سے خوب واقف ہوں.حضرت عمر کا واقعہ گزشتہ سطور میں درج کیا جاچکا ہے کہ چلے تو ہیں بانی اسلام کا قصہ
ختم کرنے (نعوذ باللہ ) لیکن قرآن کریم کی تلاوت سُن کر کایا پلٹ جاتی ہے اور مسلمان ہو جاتے ہیں.نجاشی شاہ
حبشہ تلاوت قرآن کریم سُن کر ایسا متاثر ہوتا ہے کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں.اور تو اور درباریوں
کے دل بھی گداز ہو جاتے ہیں.مختصر یہ کہ عربی زبان کے جاننے والے، اور عام جاننے والے نہیں بلکہ اہل کمال زبان دان، با تمیز مذہب و عقیدہ
اس شان سے اور اس کھلے دل کے ساتھ قرآن کریم کے حسن بیان کا اقرار کرتے ہیں کہ مسلمان ہو جاتے ہیں.جو
مسلمان نہیں ہوتے وہ بھی اس غیر معمولی حسن بیان کی تاب نہ لاکر سراسیمہ ہو جاتے ہیں اور کبھی اسے شعر وخن قرار
دیتے اور کبھی سحر، کبھی کہتے کہ واضح طور پر محمد(ﷺ) کی طاقت سے بالا کلام ہے جسے کوئی کمیٹی لکھ رہی ہے اور کبھی
اس کی علوشان کے اعتراف میں شعر کہنے چھوڑ دیتے.پس آج اگر کوئی اعتراض کرے اور ساتھ ہی یہ اقرار بھی کرے
کہ وہ عربی زبان سے واقف نہیں ہے تو لاز م یہ ماننا پڑے گا کہ وہ تعصب کے اندھیروں میں بھٹک رہا ہے یا جہالت
کی وادیوں میں سرگرداں ہے یا پھر کسی کے خون سے اپنے گناہ بخشوانے ، یا کسی انسان یا جانور یا پھر کو خدا ماننے جیسے
غیر معقول عقائد کی وجہ سے اس کا دماغ چل گیا ہے.قرآن کے حسنِ بیان کے غیر معمولی ہونے کا اہل کمال عربی
دانوں نے ایسا اقرار کیا جیسا تاریخ میں اور کسی ادب پارے کو نصیب نہ ہوا پھر کیسے ممکن ہے ایک بلند ادبی مقام کا
حامل اور صدیوں سے اُفق ادب پر جگمگانے والا لبید جیسا ستارہ تو قرآن کریم کے حسن اور ترتیب کا اقرار کرے اور آج
ایک عربی سے نابلد اٹھ کر یہ اعتراض کر دے کہ قرآن کریم حسنِ کلام سے عاری اور غیر مربوط ہے اور اس کے اعتراض
میں وزن ہو؟ قرآن کریم کے نزول کے دور میں عربی شاعری حسنِ کلام پر کھنے کی سب سے بڑی کسوٹی تھی.اگر
Page 234
الذكر المحفوظ
218
قرآن کریم کی زبان میں کوئی حسن اور ترتیب نہیں تھی تو کیوں اہل زبان اسے شاعری سے تشبیہ دیتے؟ یادر ہے کہ
تشبیہ تو دیتے مگر ساتھ ہی اقرار کرتے کہ اپنے حسن میں یہ کلام شعراء کے کلام سے بہت حسین ہے.چنانچہ یہ تشبیہ
صرف حسنِ کلام کے اعتراف کے طور پر ہوتی.کیونکہ ان کے پاس یہی سب سے بڑا پیمانہ تھا.پس اگر کلام میں
خوبصورتی یہ تھی تو کیا ساری قوم کا دماغ خراب ہو گیا تھا کہ اسے اعلیٰ درجہ کا کلام ماننے لگے؟
شعر کی تعریف میں مخصوص اوزان اور بحور کی قید اور ارکان افاعیل کی ایجاد بعد کی ہے.اساتذہ شعر وادب
نے بھی اوزان و بحور کی شرط کو ہر مقام پر قابل اعتماد نہیں سمجھا.قرآن کریم تو اس شرط کو یکسر قبول نہیں کرتا.قرآن کا
ایک اپنا زیر و بم اور آہنگ ہے.جو بہت دل پذیر ہے قرآن کریم جہاں پر عقلی استدلال اور علمی تعلیم و تدریس
بیان فرماتا ہے وہاں پر اس کا اسلوب و طرز بیان عقل و فہم کو جگانے اور منطقی استدلال کے لیے ہے اور جس مقام
پر باری تعالیٰ اپنی ذات وصفات کی عظمت و جلال اور حسن و جمال بیان فرماتا ہے وہاں پر اس کا اسلوب وطرزِ
بیان قلب و روح کی تسخیر اور فدائیت کے لیے ہے.حضرت عمرؓ مکہ کے چند پڑھے لکھے افراد میں شمار ہوتے تھے اور قادر الکلام مقرر تھے اور عربی ادب پر نظر
رکھنے والے انسان تھے.مسند احمد بن حنبل کی ایک روایت ہے:
حضرت عمرؓ بن خطاب کہتے ہیں کہ میں اسلام لانے سے قبل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
نظروں سے بچتے ہوئے آپ کے پیچھے پیچھے چلا جارہا تھا اور آپ میرے آگے آگے مسجد میں
داخل ہوئے اور سورۃ الحاقہ کی تلاوت شروع کی.میں پہلے تو قرآن کی تالیف سے متعجب ہوا پھر
تلاوت سننے پر دل میں کہا بخدا یہ تو شاعر ہیں.جیسا کہ قریش کہا کرتے تھے.آپ نے یہ آیت
پڑھی إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُوْلِ كَرِيمٍ وَ مَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ “اس پر میں نے
دل میں کہا یہ تو صحیح ہے.مگر کا ہن بھی تو ایسی پیشگوئیاں کرتے ہیں.تو آپ نے اس آیت ولا
بِقَوْلِ كَاهِنِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ تَنْزِيلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعَالَمِينَ.وَ لَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ
الأقَاوِيلَ...حاجزِینَ “ سے سورت کے آخر تک تلاوت کی.حضرت عمر فرماتے ہیں کہ
میرے ہر سوال کے جواب پر میرے دل میں اسلام راسخ ہوتا چلا گیا.66
(مسند احمد بن حنبل مسند عشرة المبشره اول مسند..عمر بن الخطاب)
حیرت کی بات ہے کہ سبعہ معلقات کے سامنے ہوتے ہوئے لبید بن ربیعہ عامری جیسا مشہور زمانہ شاعر طفیل
بن دوسی جیسی ادبی شخصیت ، ضمار از دی جیسا سحر، بیان ولید بن مغیرہ جیسا عارف شعر ونحن نجاشی جیسا صاحب سطوت اور
حضرت عمر جیسا ایک اہلِ علم زبان دان، جو اپنی سخن فہمی کی بنا پر فصیح و بلیغ عرب کے سفیر کا رتبہ رکھتا جب قرآن سٹنا ہے تو
اس کے غیر معمولی حسن وربط اور حسن نظم کی وجہ سے اُسے انسانی طاقت سے بالا و اعلی کلام تسلیم کرتا ہے اور ابن وراق ایک
Page 235
قرآن کریم میں تحریف کے الزامات کے جواب
219
عربی سے ناواقف ہونے کا اعتراف کرتا اور ساتھ ہی قرآن کریم پر زبان طعن دراز کرتا ہے.جارج سیل کہتا ہے:
The Style of the Koran is generally beautiful and fluent
(George Sale: The Koran; The Preliminary Discourse; Section
3; pg: 48)
یعنی قرآن کریم کا سٹائل عمومی طور پر دلکش اور سلیس ہے
کیرم آرمسٹرانگ قرآن کریم کے سحر انگیز حسن کے بارہ میں لکھتی ہیں:
خود عربوں کے بیان کے مطابق اسے پڑھنا ان کے لیے ہمیشہ ایک مختلف تجر بہ ثابت ہوا ہے.اس
کی زبان میں بلا کی خوبصورتی ہے جس کی مثال سارے عربی کلاسیکی ادب میں کہیں نہیں ملتی.محمد ( ﷺ ): باب دوم، صفحہ 63-61 پبلشرز، علی پلاز 30 مزنگ روڈلا ہور )
الغرض عرب جنہیں اپنی زبان دانی، فصاحت و بلاغت اور زور بیان پر ناز تھا قرآن مجید انہی کی زبان میں
اُترا اور انہی کے اسلوب اور طرز ادا کو اس نے اختیار کیا، انہوں نے اس کو سمجھا اور اس کی علو شان کی گواہی دی.اس کی سحر طرازیوں نے سب سے پہلے انہیں ہی اپنا گرویدہ بنایا اور انہی پر اپنا اثر دکھایا.اہل زبان میں سے جس
نے اس کو سُنا وہ اس کی عظمت اور برتری کا اعتراف کیے بغیر نہ رہ سکا.ان میں سے جن پاکیزہ نفوس نے اس کی
دعوت پر لبیک کہا انہی کو اس سے پورا پورا فائدہ پہنچا.حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں:
آپ خاتم النبین ٹھہرے اور آپ کی کتاب خاتم الکتب ٹھہری.جس قدر مراتب اور وجوہ اعجاز
کلام کے ہو سکتے ہیں.ان سب کے اعتبار سے آپ کی کتاب
انتہائی نقطہ پر پہنچی ہوئی ہے.یعنی کیا باعتبار فصاحت و بلاغت، کیا باعتبار ترتیب مضامین، کیا باعتبار تعلیم ، کیا باعتبار
کمالات تعلیم، کیا باعتبار ثمرات تعلیم ، غرض جس پہلو سے دیکھو اسی پہلو سے قرآن شریف کا
کمال نظر آتا ہے اور اس کا اعجاز ثابت ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ قرآن شریف نے کسی خاص
امر کی نظیر نہیں مانگی ، بلکہ عام طور پر نظیر طلب کی ہے.یعنی جس پہلو سے چاہو مقابلہ کرو.خواہ
بلحاظ فصاحت و بلاغت خواه بلحاظ مطالب و مقاصد خواہ بلحاظ تعلیم خواہ بلحاظ پیشگوئیوں اور غیب
کے جو قرآن شریف میں موجود ہیں.غرض کسی رنگ میں دیکھو، یہ مجزہ ہے.( ملفوظات جلد 2 صفحہ 26 27 مطبوعہ ربوہ )
وہ عرب جو اپنی شقاوت قلبی اور ہٹ دھرمی کے باعث قرآن کریم کی صداقت پر ایمان نہیں لائے ، وہ بھی کم
از کم یہ تسلیم کرنے پر مجبور دکھائی دیتے ہیں کہ قرآن کریم اعلی ترین فصیح و بلیغ عربی کلام ہے.چنانچہ تاریخ میں ذکر
ملتا ہے کہ عرب قرآن کریم کے غیر معمولی حسن سے اس درجہ متاثر تھے کہ اسے سحر قرار دیتے تھے.قرآن کریم اُن
کے اس اقرار کو ان الفاظ میں بیان کرتا ہے:
Page 236
الذكر المحفوظ
220
وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمُ ايْتُنَا بَيِّنَتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَ هُمْ هَذَا
28
سِحْرٌ مُّبِينٌ (احقاف :8)
اور جب ان پر ہماری کھلی کھلی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ لوگ، جنہوں نے حق کا انکار کر دیا
جب وہ ان کے پاس آیا ، کہتے ہیں یہ تو سحر ہے.حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں:
جنہوں نے قرآن شریف کے بے مثل کمالات پر غور کی اور اس کی عبارت کو ایسے اعلیٰ درجہ
کی فصاحت اور بلاغت پر پایا.کہ اس کی نظیر بنانے سے عاجز رہ گئے اور پھر اس کے دقائق وحقائق
کو ایسے مرتبہ عالیہ پر دیکھا کہ تمام زمانہ میں اس کی نظیر نظر نہ آئی اور اس میں وہ تاثیرات عجیبہ
مشاہدہ کیں کہ جو انسانی کلمات میں ہر گز نہیں ہوا کرتیں اور پھر اس میں یہ صفت پاک دیکھی کہ
وہ بطور رہنرل اور فضول گوئی کے نازل نہیں ہوا.بلکہ عین ضرورت حقہ کے وقت نازل ہوا.تو
انہوں نے ان تمام کمالات کے مشاہدہ کرنے سے بے اختیار اس کی بے مثل عظمت کو تسلیم کر لیا
اور ان میں سے جو لوگ باعث شقاوت از لی نعمت ایمان سے محروم رہے.ان کے دلوں پر بھی
اس قدر ہیبت اور رعب اس بے مثل کلام کا پڑا کہ انہوں نے بھی مبہوت اور سراسیمہ ہو کر یہ کہا
کہ یہ تو سحر مین ہے اور پھر منصف کو اس بات سے بھی قرآن شریف کے بے مثل و مانند ہونے
پر ایک قوی دلیل ملتی ہے اور روشن ثبوت ہاتھ میں آتا ہے کہ باوجود اس کے مخالفین کو تیرہ سو برس
سے خود قرآن شریف مقابلہ کرنے کی سخت غیرت دلاتا ہے اور لا جواب رہ کر مخالفت اور انکار
کرنے والوں کا نام شریر اور پلید اور لعنتی اور جہنمی رکھتا ہے.مگر پھر بھی مخالفین نے نامردوں اور
مخنثوں کی طرح کمال بے شرمی اور بے حیائی سے اس تمام ذلت اور بے آبروئی اور بے عزتی کو
اپنے لیے منظور کیا اور یہ روا رکھا کہ ان کا نام جھوٹا اور ذلیل اور بے جا اور خبیث اور پلید اور شریر اور
بے ایمان اور جہنمی رکھا جاوے.مگر ایک قلیل المقدار سورۃ کا مقابلہ نہ کر سکے اور نہ ان خوبیوں اور
صفتوں اور عظمتوں اور صداقتوں میں کچھ نقص نکال سکے کہ جن کو کلام الہی نے پیش کیا ہے.(براہین احمدیہ جلد چہارم حاشیہ نمبر گیارہ روحانی خزائن جلد اول صفحہ 432,433 ایڈیشن اول
صفحہ 363 362)
کیرم آرمسٹرانگ اس بارہ میں رقم طراز ہیں:
لوگوں کے دائرہ اسلام میں آنے کی بنیادی وجہ خود قرآن مجید کی کشش تھی.چنانچہ 16 ہجری
میں حج کے موقع پر جب مختلف علاقوں سے زائرین خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے آئے تو ابوجہل
Page 237
قرآن کریم میں تحریف کے الزامات کے جواب
221
نے اپنے ساتھیوں کو مکہ کے تمام دروازوں پر کھڑا کر دیا جو آنے والوں کو متنبہ کرتے کہ
( حضرت ) محمد (ع) سے خبر دار ہیں کہ وہ اپنے کلام کے سحر سے لوگوں کو گمراہ کرنے میں
ماہر ہیں.ان میں سے ایک زائر سوید ابن عمر جو شاعر تھا، اس تنبیہ سے اس قدر خوف زدہ ہوا کہ
اس نے اپنے کانوں میں روئی کی پھوئیاں ٹھونس لیں تا کہ نبی کریم اسے کچھ کہنے کی کوشش بھی
کریں تو اسے ان کے الفاظ سنائی ہی نہ دیں اور وہ آپ کے جادو کا اسیر ہونے سے محفوظ رہے.لیکن جب وہ خانہ کعبہ کے اندر گیا اور حضرت محمد (ﷺ) کو کھڑے عبادت کرتے دیکھا تو یہ
سوچ کر اسے شرمندگی محسوس ہوئی کہ میں ایک بالغ اور باشعور انسان ہوں.میں سوچ سمجھ سکتا
ہوں پھر کیا وجہ ہے کہ میں اس بات سے اتنا خوف زدہ ہوں کہ کوئی مجھے محض اپنے الفاظ کے جادو
سے گمراہ کر سکتا ہے.کیا مجھے اپنی دانش پر اعتبار نہیں جو اچھے اور برے میں تمیز کرنے میں ہمیشہ
میری معاون ہوتی ہے.وہ (حضرت ) محمد (ﷺ) کے قریب گیا.آپ نے اسے اسلام کی
تبلیغ کی اور اسلامی تعلیمات سے آگاہ کیا.پھر قرآن کریم کی چند آیات کی تلاوت فرمائی.تلاوت سن کر سوید ابن عمر اس قدر حیران ہوا کہ کہنے لگا، اللہ کی قسم ! میں نے اس سے بہتر شے
نہ کہیں پڑھی اور نہ کبھی سنی ہے.“ اس نے فوراً ہی اسلام قبول کرلیا.اور واپس جا کر اگلے چند
سالوں میں اپنے قبیلہ میں تقریباً ستر خاندانوں کو مشرف بہ اسلام کیا.قرآن مجید میں کلام کی خوبصورتی اور اثر انگیزی نے عربوں کے دلوں کو اسیر کر لیا.(حضرت)
طفیل بن عمرو نے تو خود ہی کانوں میں ٹھونسی ہوئی روٹی نکال لی اور نبی کریم سے درخواست کی تھی
کہ آپ ان کے لیے قرآن کریم کی آیات تلاوت فرمائیں.لیکن بہت سے ایسے بھی تھے کہ جو خود
کو اس اثر سے محفوظ رکھنے میں کامیاب ہوئے جن میں ابو جہل اور اس کے ساتھی شامل تھے.محمد ( ﷺ ) : باب ششم ، صفحہ 159 - 158 پبلشرز علی پلاز 30 مزنگ روڈلاہور )
ان ابو جہل کے ساتھیوں میں ایک خاص ساتھی ابن وراق آج ایک اور پینترا بدلتا ہے.محافظت قرآن کے
ضمن میں شک پیدا کرنے کی غرض سے ابن وراق موجودہ ترتیب پر اعتراض کرتے ہوئے یہ تاثر دینے کی کوشش
کرتا ہے کہ کثرت سے تحریف و تبدل کی وجہ سے قرآن کریم حسنِ کلام سے بالکل عاری ہو چکا ہے.کہتا ہے:
Unevenness of the Koranic style....abrupt changes of
rhyme; repetition of the same thyme word or rhyme
phrase in adjoining verses;
(Ibn Warraq: Why I am Not A Muslim, Prometheus Books, New
York, 1995, under heading; The Koran: Pg :112)
یعنی اسلوب قرآن غیر متوازن ہے.انداز میں بے تحا شا ہد لا و؛ آیات میں ایک ہی قسم
Page 238
الذكر المحفوظ
222
کے الفاظ یا جملوں کی تکرار ؛
اب کوئی بھی صاحب عقل و خرد کس طرح تسلیم کرلے کہ ابن وراق کی بات درست ہے اور ساری عرب قوم
اور پندرہ سو سال کے طویل عرصہ میں دُنیا کے ہر کونے میں پیدا ہونے والے سخن فہم ، اہل زبان اور اہل علم غلطی
خوردہ ہیں؟ اگر در حقیقت ایسا نہیں تھا تو پھر شعر و شاعری کے دلدادہ اور ہزاروں ہزار شعر یا درکھنے والے وہ لوگ
اور کثرت سے شعر وسخن کی مجالس منعقد کرنے والی وہ قوم کیوں قرآن کریم کے غیر معمولی حسن کا اعتراف کرتے
اور کلام بھی ایسا حسین و دلنواز کہ سامع کو مسحور کر دے.پس یا تو قرآن کریم کے عدیم النظیر ہونے کا اعتراف
کرتے ہوئے حلقہ بگوش اسلام ہو جاتے ہیں یا پھر سراسیمہ ہو کر چپ سادھ لیتے ہیں یا کبھی لب کھولتے بھی ہیں تو
سحر سحر پکارنے لگ جاتے ہیں.پھر جو اہل زبان کھل کر اس کا اعتراف کرتے ہیں وہ بھی اس شان سے کرتے
ہیں کہ اور کسی کلام کے حسن کو اس زور سے تسلیم نہیں کیا گیا.حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں:
جس کلام کی بلاغت کو عرب کے تمام اہل زبان جن میں بڑے بڑے شاعر بھی تھے باوجود
سخت مخالفت کے تسلیم کر چکے ہیں.بلکہ بڑے بڑے معاند اس کلام کی شان عظیم سے نہایت
درجہ تعجب میں پڑگئے اور اکثر ان میں سے کہ جو فصیح اور بلیغ کلام کے اسلوب کو بخوبی جاننے
پہچاننے والے اور مذاق سخن سے عارف اور بانصاف تھے.وہ طرز قر آنی کو طاقت انسانی سے
باہر دیکھ کر ایک معجز عظیم یقین کر کے ایمان لے آئے جن کی شہادتیں جابجا قرآن شریف میں
درج ہیں اور جو لوگ سخت کو رباطن تھے اگر چہ وہ ایمان نہ لائے.مگر سراسیمگی اور حیرانی کی
حالت میں ان کو بھی کہنا پڑا کہ یہ سحر عظیم ہے جس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا چنانچہ ان کا یہ بھی بیان
فرقان مجید کے کئی مقام میں موجود ہے.اب اسی کلام معجزہ نظام پر ایسے لوگ اعتراض کرنے
لگے جن میں سے ایک تو وہ شخص ہے جس کو دوسطر میں عربی کی بھی صحیح اور بلیغ طور پر لکھنے کا ملکہ
نہیں اور اگر کسی اہل زبان سے بات چیت کرنے کا اتفاق ہو تو بجز ٹوٹے پھوٹے اور بے ربط اور
غلط فقروں کے کچھ بول نہ سکے اور اگر کسی کو شک ہو تو امتحان کر کے دیکھ لے اور دوسرا وہ شخص ہے
جو علم عربی سے بلکلی بے بہرہ بلکہ فارسی بھی اچھی طرح نہیں جانتا اور افسوس کہ عیسائی مقدم الذکر
کو یہ بھی خبر نہیں کہ یورپ کے اہل علم کہ جو اس کے بزرگ اور پیشرو ہیں.جن کا بورٹ صاحب
وغیرہ انگریزوں نے ذکر کیا ہے وہ خود قرآن شریف کے اعلیٰ درجہ کی بلاغت کے قائل ہیں اور
پھر دانا کو زیادہ تر اس بات پر غور کرنی چاہیے کہ جب ایک کتاب جو خود ایک اہل زبان پر ہی
Page 239
قرآن کریم میں تحریف کے الزامات کے جواب
223
نازل ہوئی ہے اور اس کی کمال بلاغت پر تمام اہل زبان بلکہ سبعہ معلقہ کے شعراء جیسے اتفاق
کر چکے ہیں.تو کیا ایسا مسلم الثبوت کلام کسی نادان اجنبی وژولیدہ زبان والے کے انکار سے جو
که لیاقت فن سخن سے محض بے نصیب اور تو غل علوم عربیہ سے بالکل بے بہرہ بلکہ کسی ادنیٰ عربی
آدمی کے مقابلہ پر بولنے سے عاجز ہے قابل اعتراض ٹھہر سکتا ہے بلکہ ایسے لوگ جو اپنی حیثیت
سے بڑھ کر بات کرتے ہیں خود اپنی نادانی دکھلاتے ہیں اور یہ
نہیں سمجھتے کہ اہل زبان کی شہادت
کے برخلاف اور بڑے بڑے نامی شاعروں کی گواہی کے مخالف کوئی نکتہ چینی کرنا حقیقت میں اپنی
جہالت اور خطر فطرتی دکھلانا ہے.بھلا عماد الدین پادری کسی عربی آدمی کے مقابلہ پر کسی دینی یا
دنیوی معاملہ میں ذرا ایک آدھ گھنٹہ تک ہم کو بول کر تو دکھاوے.تا اول یہی لوگوں پر کھلے کہ اس کو
سیدھی سادھی اور بامحاورہ اہل عرب کے مذاق پر بات چیت کرنی آتی ہے یا نہیں.کیونکہ ہم کو
یقین ہے کہ اس کو ہرگز نہیں آتی اور ہم یہ یقین تمام جانتے ہیں کہ اگر ہم کسی عربی آدمی کو اس کے
سامنے بولنے کے لیے پیش کریں تو وہ عربوں کی طرح اور ان کے مذاق پر ایک چھوٹا سا قصہ بھی
بیان نہ کر سکے اور جہالت کے کیچڑ میں پھنسا رہ جائے اور اگر شک ہے.تو اس کو قسم ہے کہ آزما کر
دیکھ لے! پھر جس حالت میں وہ عربوں کے سامنے بھی بول نہیں سکتے اور فی الفور گونگا بننے کے
لیے طیار ہیں.تو پھر ان عیسائیوں اور آریوں کی ایسی سمجھ پر ہزار حیف اور دو ہزار لعنت ہے کہ جو
ایسے نادان کی تالیف پر اعتماد کر کے اس بے مثل کتاب کی بلاغت پر اعتراض کرتے ہیں کہ جس
نے سید العرب پر نازل ہو کر عرب کے تمام فصیحوں اور بلیغوں سے اپنی عظمت شان
کا اقرار کرایا
اور جس کے نازل ہونے سے سبعہ معلقہ مکہ کے دروازہ پر سے اتارا گیا اور معلقہ مذکورہ کے
شاعروں میں سے جو شاعر اس وقت بقید حیات تھا.وہ بلا توقف اس کتاب پر ایمان لایا.براین حد به جلد چهارم حاشیه نبر گیاره وحانی خزائن جلد اول صفحہ 432,433ایڈیشن اول صفحہ 362,363)
حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب خلیفہ المسح الثاني لمصلح الموعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:
اس کا ( یعنی قرآن کا ) ظاہری حسن اتنا نمایاں ہے کہ کوئی کتاب اس کے سامنے ٹھہر ہی نہیں
سکتی.الفاظ کی خوبی، بندش کی چستی محاورہ کا برمحل استعمال ، عبارت کا تسلسل مضمون کی رفعت،
معانی کی وسعت ایک سے ایک بڑھ کر خوبیاں ہیں کہ انسان نہیں کہ سکتا کہ اُسے سرا ہے یا اس
کی تعریف کرے.انہی عربی الفاظ سے وہ بنا ہے جو ہزاروں لاکھوں اور کتب میں استعمال
ہوئے ہیں مگر کیا مجال کہ کوئی اور کتاب اس کے قریب تک پہنچ سکتی ہو.عرب اپنے خیالات کی
Page 240
الذكر المحفوظ
224
نزاکت اور اپنے ادب کی بلندی اور اپنے ذخیرہ الفاظ کی کثرت کی وجہ سے سب دنیا کے لوگوں
پر فوقیت رکھتے ہیں اور عرب قوم ادب کی اس قدر دلدادہ ہے کہ زہر اور زر اور علوشان جیسی
آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی اشیاء بھی اُن کے نزدیک ادب کے مقابلہ پر پیچ ہیں.وہ اپنے
شاعروں کو پیغمبر اور اپنے ادیبوں کو دیوتا سمجھنے والے لوگ جن میں ادب اور ادیب کو ترقی کرنے کا
بہترین موقع مل چکا تھا جب قرآن کو دیکھتے ہیں تو زبانوں پر مہر لگ جاتی ہے اور آنکھیں چندھیا
جاتی ہیں.باوجود اس کے کہ نزول قرآن کریم کا زمانہ ان کا بہترین ادبی زمانہ تھا.یا تو عرب
کے چوٹی کے ادیب قریب میں ہی گزر چکے تھے یا ابھی زندہ موجود تھے.وہ جب قرآن کریم کو
سنتے ہیں تو بے اختیار اس کے سحر ہونے کا شور مچادیتے ہیں.مگر وہی لفظ جو اس کے جھوٹا ہونے
کے ثبوت کے طور پر استعمال کیا گیا تھا.اسی نے ظاہر کر دیا کہ عرب کا متفقہ فیصلہ تھا کہ قرآن
کریم کا حسن انسانی قوت تخلیق سے بالا تھا.انسانی دماغ نے بہتر سے بہتر ادبی مقالات بنائے
تھے.مگر اس جگہ اسے اپنے عجز کا اعتراف کیے بغیر کوئی چارہ نہ تھا.فسبحان الله احسن الخالقین.ا
اس کے مضامین کا بھی یہی حال ہے ان کی بلندی ، ان کی وسعت، ان کی ہمہ گیری، ان کا
انسانی دماغ کے گوشوں کو منور کر دینا، انسانی قلوب کی گہرائیوں میں داخل ہو جانا ، نرمی پیدا کرنا تو
اس قدر کہ فرعونیت کے ستونوں پر لرزہ طاری ہو جائے ، جرات پیدا کرنا تو اس حد تک کہ بنی
اسرائیل کے قلوب بھی ابراہیمی ایمان محسوس کرنے لگیں، عفو کو بیان کرے تو اس طرح کہ عیسی
علیہ السلام بھی انگشت بدنداں ہو جائیں ، سزا کی ضرورت ظاہر کرے تو اس طرح کہ موسی کی
روح بھی صل علی کہہ اُٹھے غرض بغیر اس کے مضامین کی تفاصیل میں پڑنے کے ہر انسان سمجھ سکتا
ہے کہ وہ ایک سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں ایک باغ ہے جس کے پھلوں
کا خاتمہ نہیں.آج تک
اُس کے حسن کو دیکھ کر لوگ یہ کہتے چلے جاتے ہیں کہ یہ کلام بہت سے لوگوں نے مل کر بنایا ہے
مگر کیا یہ خود اقرار حسن نہیں؟
( تفسیر کبیر جلد ۳ صفحه 469 زیرتفسیر سورۃ ابراہیم :25)
مشہور مستشرق قلب کے حتی لکھتا ہے:
یہ کتاب ایک قوی اور زندہ آواز ہے.اس کو زبان سے پڑھنے اور اس کے اصل متن کوسننے سے
اس
کی حقیقی قدرومنزلت پہچانی جاسکتی ہے.اس کی قوت تاثیر زیادہ تر اس کے منفر دانداز لجن، ترتیل،
اور الفاظ کے سُبک پن میں مضمر ہے.اس کی یہ خصوصیت ترجمہ میں منتقل کی ہی نہیں جاسکتیں.تاریخ عرب از فلپ کے حتی ، ناشر : آصف جاوید برائے نگارشات ، باب 4 صفحہ 36 )
Page 241
قرآن کریم میں تحریف کے الزامات کے جواب
225
ابن وراق اپنے اندھے پن کی وجہ سے جسے abrupt changes کہ رہا ہے وہ دراصل قرآن کریم کا ایک
معجزانہ اسلوب بیان ہے جس کا حسن غیر معمولی ہے اور ایسا بھی نہیں کہ جب اعتراض ہوا ہے تو مسلمانوں کو اس کا
جواب دینے کے لیے اس مسئلہ کو زیر بحث لانا پڑا ہے.نزول قرآن کے وقت سبعہ معلقات کے اُس دور میں
جب عربی فصاحت و بلاغت کی رفعتوں کو چھو رہی تھی ، قرآن کریم اپنی اس خصوصیت کو بآواز بلند بار بار تصریف آیات
کی اصطلاح کے ساتھ بیان کرتا ہے اور قاری کو دعوت دیتا ہے کہ دیکھو خدا تعالیٰ کس خوبصورت انداز میں اس
مضمون
کو باندھ رہا ہے.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:
أنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الآيتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ (الانعام: 47)
دیکھو تو سہی کہ ہم کس طرح آیات کو پھر پھیر کر بیان کرتے ہیں.پھر وہ منہ پھیر لیتے ہیں.اس آیت میں اُنظر کے الفاظ میں قاری کو یہ بتایا گیا ہے کہ تصریف الآیات کے معجزہ کو سمجھنے کے لیے غور کی
ضرورت ہے.بناغور سے دیکھے اس کو سمجھنا محال ہے اور لطف یہ ہے کہ جواب میں کوئی اہل زبان دم نہیں مارتا.ثُمَّ هُمُ
يَصْدِقُونَ کے الفاظ میں بتادیا کہ اہل زبان عرب تو جو قرآن کریم پر ایمان نہیں لاتے وہ اس معجزہ کا جواب نہیں
دے پاتے اور اعراض کرتے ہیں گجایہ کہ کوئی ایسا جاہل ہو عربی زبان کی ابجد سے بھی واقف نہ ہواور محض ہرزہ سرائی
کرتے ہوئے اور تعصب اور جہالت کی بنیاد پر لچر اور کھوکھلے اعتراضات کی پٹاری کھول کر بیٹھ جائے.اس طرز تحریر میں ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جگہ جگہ قاری کا ذہن بار بار چوکس ہوتا ہے اور تحریر اپنے اس
مخصوص انداز سے بار بار قاری کے ذہن کو جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر بیدار کرتی ہے.قاری فوراً اس انوکھے انداز پر چوکنا
ہو کر مضمون سے گزرتا ہے اور ہر آیت کو غور سے پڑھتا ہے اور یہ بات تو ہر شخص سمجھتا ہے کہ سوئے ہوئے دماغ اور
مستعد دماغ کے مشاہدہ میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے.پس یہ انسانی فطرت اور نفسیات کو بتمام و کمال مد نظر
رکھ کر پیش کیا جانے والا کلام ہے اور صرف اسی ہستی کی طرف سے ہوسکتا ہے جو انسانی فطرت اور نفسیات کی کننہ
سے واقف ہو.کسی انسان کی مجال نہیں کہ ان حکمتوں کو پہنچ بھی سکے جن پر پورا اترتے ہوئے یہ کلام انسان کو دیا گیا.جرمن زبان کا مشہور انشاء پرداز گیئے جسے جرمن زبان کا شیکسپئر کہا جاتا ہے،لکھتا ہے:
قرآن کریم کی عبارت پہلے پہل پڑھنے والے کو بے جوڑ اور بے ربط معلوم ہوتی ہے لیکن
جو نہی کہ وہ وہ اسے مکرر پڑھتا اور اس پر زیادہ غور کرتا ہے تو وہ ہمیشہ اُسے معارف کی گہرائیوں
میں لے جاتی ہے اور بہت اعلیٰ معلوم ہوتی ہے اور اپنے پڑھنے والے کو مسخر بلکہ مسحور کر دیتی ہے
اور بالآخروہ پڑھنے والا اس کے محیر العقل انداز بیان اور معجزانہ حسن ونظم میں بالکل کھو کر رہ جاتا ہے.(Adictionary of Islam by Thomas Patrich Huyheis P:526)
( ریویو آف ریجنز مئی ۱۹۳۳ صفحه ۱۲)
Page 242
الذكر المحفوظ
226
گئے جیسے سخن ور اور سخن فہم شخص کی یہ گواہی عام نظر سے دیکھی جانے والی نہیں.کیرم آرمسٹرانگ قرآن کریم کے سحر انگیز حسن کو ان الفاظ میں بیان کرتی ہیں :
اہل عرب کے لیے قرآن مجید کی عبارت
واقعتا معجز نما تھی.ان کے ادب میں اس طرح کی
کوئی چیز پہلے موجود نہیں تھی.کچھ تو فورا ہی ان آیات پر یہ یقین کرتے ہوئے ایمان لے
آئے کہ اس غیر معمولی زبان میں موجود پیغام الہامی اور سچا ہی ہوسکتا ہے.لیکن جوان تعلیمات پر
ایمان نہیں لائے وہ گومگو کی کیفیت میں رہے.انہیں سمجھ نہیں آرہا تھا کہ اس دعوت کا کیا جواب دیں.( محمد ( ﷺ ) : باب دوم صفحہ 63-61 پبلشرز علی پلازہ 3 مزنگ روڈ لاہور )
سیل کی ایک گواہی گزر چکی ہے.قرآن کریم کے حسن بیان کے معجز نما ہونے کے بارہ میں لکھتا ہے:
And to this miracle did Mohammed himself chiefly
appeal for the confirmation of his mission, publicly
challenging the most eloquent men in Arabia, which was
at that time stocked with thousands whose sole study
and ambition it was to excel in elegance of Style and
composition, to produce even a single chapter that
might be compared with it.I will mention but one
instance out of several, to show that this book was really
admired for the beauty of its composure by those who
must be allowed to have been competent
judges.....declaring that such words could proceed from
an inspired person only.(George Sale: The Koran; The Preliminary Discourse; Section
3; pg: 47,48)
اور یہ معجز نما حقیقت محمد (ﷺ) نے خود اہل مکہ کے سامنے رکھی اور مشہور اہل زبان اور
ماہرین سخن کو جو اس دور میں عرب میں ہزاروں کی تعداد میں موجود تھے، ایک عام چیلنج دیا کہ اس
کلام سے بڑھ کر حسین کلام بنا کر دکھا دیں اس کے کسی ایک حصہ کے بالمقابل ہی بنا
دیں.میں بیسیوں مثالوں میں سے ایک مثال کا انتخاب کرتا ہوں تا کہ یہ ثابت کرسکوں کہ یہ
کتاب در حقیقت ایسے لوگوں کے سامنے پیش کی گئی تھی جو فیصلہ کرنے کی طاقت رکھتے
تھے.اس کے بعد لبید بن ربیعہ عامری کی مثال پیش کرتا ہے کہ وہ فوری طور پر قرآن کریم
پر ایمان لے آئے اس لیے کہ انہوں نے یہ تسلیم کر لیا کہ یہ غیر معمولی کلمات ایک ملہم کو
ہی عطا ہو سکتے ہیں.
Page 243
قرآن کریم میں تحریف کے الزامات کے جواب
227
لیکن حیرت ہے کہ عربی زبان کا گہرا علم نہ رکھنے والے اور اس کی بلاغت کے اصولوں سے بیجبر، جن کو عربی
بول چال کا بھی ملکہ نہیں اعتراض کرتے ہیں.پس آج اس تعریف آیات کے معجزہ کو اگر کوئی abrupt
changes کہہ دے تو یہ اس کی جہالت ہے نہ کہ قرآن کی خامی.اسے فورا عظیم اہل زبان عرب لوگوں سے
پوچھنا چاہیے اور ابن وراق کے لیے سیوطی کی گواہی کافی ہوگی.کیوں کہ اسے بھی تسلیم ہے کہ علامہ سیوطی ایک
عظیم ماہر لسانیات ہیں.(Ibn Warraq: Why I am Not A Muslim, Prometheus Books, New
York, 1995, under heading; The Koran: Sub Heading; The Word
of God? Pg; 106)
علامہ سیوطی ایک فخر اور تحدی سے فرماتے ہیں:
لا ترى شيئا من الالفاظ افصح ولا اجزل و لا اعذب من الفاظه و لا ترى
نظما احسن تاليفا و اشد تلاوة و تشاكلا من نظمه -
(الاتقان في علوم القرآن الجزء الثانى النوع الرابع والستون في اعجاز القرآن)
یعنی اے مخاطب تجھے قرآن کریم کے الفاظ سے زیادہ فصیح ، پر شوکت اور شیریں الفاظ کبھی
کسی کلام میں نظر نہیں آئیں گے.اس سے زیادہ منظوم اور مربوط اور شاندار ترتیب والا اور زور
دار کلام تو کبھی نہ دیکھ پائے گا.پس ابن و راق اور کسی کی نہیں سنتا تو بیشک نہ سنے ، اپنی بات کو وقعت دیتے ہوئے علامہ سیوطی کی ہی سُن لے
اور ان کے علم و فضل سے ہی فائدہ اُٹھا لے.علامہ سیوطی کے نزدیک قرآن کریم فصیح و بلیغ اور معجزانہ اسلوب بیان
والا ایک ایسا مرتب اور مربوط کلام ہے جو انسانی طاقت سے بہت بالا ہے اور خدا تعالیٰ کا کلام ہے اور ہر پہلو سے
محفوظ ہے.چنانچہ اپنی مشہور زمانہ تصنیف الاتقان کے شروع میں بھی اس حقیقت کا بڑی عقیدت اور فخر سے ذکر
کرتے ہیں اور اس کے پہلے ہی صفحہ پر قرآن کریم کی ان خوبیوں کا ذکر کرتے ہیں.اب امید ہے ابن وراق کسی
عربی سے نابلد ، متعصب مستشرق کی تحریر کو بنیاد بنانے کی بجائے اس عظیم ماہر لسانیات اور مفسر قرآن کی بات کو
اہمیت دیتے ہوئے قرآن کے معجزانہ اسلوب بیان
کو سمجھ بے شک نہ پائے لیکن تسلیم ضرور کر لے گا.اور ہو بھی
کیسے سکتا ہے کہ تسلیم نہ کرے؟ خود ہی تو مانتا ہے کہ سیوطی عظیم ماہر لسانیات ہیں.علامہ سیوطی کے علاوہ اور بھی بہت علما ہیں جنکو سیوطی بھی عربی زبان کا ماہر تسلیم کرتے ہیں اور ان علما نے بھی
صرف تصریف الآیات کے موضوع پر کتب لکھ کر قرآن کریم کے اس معجزہ کی وضاحت کی ہے.مثلا فراء نے اپنی
کتاب معانی القرآن میں اس معجزہ پر بحث اُٹھائی ہے اسی طرح امام لغت ابوعلی احمد بن جعفر دینوری المتوفی 289
کی کتاب ضمائر القرآن خاص طور پر اسی موضوع پر ہے.”التفات علم بلاغت کا باقاعدہ ایک شعبہ ہے جس میں
،،عل
Page 244
الذكر المحفوظ
228
ضمائر کی تبدیلی اور ایک واقعہ سے ایک دوسرے واقعہ کی طرف توجہ پھیر نے کے انداز وغیرہ پر گفتگو کی جاتی ہے.اس پر اعتراض کرنا یہ تو ایسی بات ہی ہوگی کہ انگریزی زبان کا سرسری ساعلم رکھنے والا شیکسپئر کا کوئی ادب
پارہ سمجھ نہ پائے اور اعتراض کر دے کہ جانے کیا کیا لکھ دیا ہے.پس بہتر یہی تھا کہ ابن وراق اہل زبان کی گواہی
کو ہی تسلیم کرتا اور اپنی جہالت کو قرآن کریم پر اعتراض کی وجہ اور بنیاد نہ بناتا.قرآن کریم تو اپنے اسلوب بیان کو
ایک چیلنج کے طور پر پیش کرتا ہے کہ اس جیسا مرتب، با ربط اور فصیح و بلیغ کلام پیش کر کے تو دکھاؤ اور اُن لوگوں کو جو
نہ چیلنج قبول کرتے ہیں اور نہ ہی قرآن کریم کا الہی کلام ہونا تسلیم کرتے ہیں جھوٹا اور شکست خوردہ قرار دیتا ہے.مگر پھر بھی پندرہ سوسال کے اس عرصے میں کسی عربی دان کو اس میدان میں دم مارنے کی جرات نہیں ہوئی اور عاجز
رہ کر خود اپنا جھوٹا اور شکست خوردہ ہونا تسلیم کر لیا.آخری طریق فیصلہ
حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس بارہ میں فرماتے ہیں:
علاوہ دلائل متذکرہ بالا کے کئی ایک اور وجوہ بھی ہیں.جن سے خدا کے کلام کا عدیم
المثال ہونا اور بھی زیادہ اس پر واضح ہوتا ہے اور مثل اجلی بدیہات کے نظر آتا ہے.جیسے
منجملہ ان کے ایک وہ وجہ ہے جو ان نتائج متفاوتہ سے ماخوذ ہوتی ہے.جن کا مختلف طور پر
بحالت عمل صادر ہونا ضروری ہے.تفصیل اس کی یہ ہے کہ ہر ایک عاقل کی نظر میں یہ بات
نہایت بدیہی ہے کہ جب چند متکلمین انشا پرداز اپنی اپنی علمی طاقت کے زور سے ایک ایسا
مضمون لکھنا چاہیں کہ جو فضول اور کذب اور حشو اور لغو اور ہنرل اور ہر ایک مہمل بیانی اور ژولیدہ
زبانی اور دوسرے تمام امور محل حکمت و بلاغت اور آفات منافی کمالیت و جامعیت سے بکلی
منزہ اور پاک ہوا اور سراسرحق اور حکمت اور فصاحت اور بلاغت اور حقائق اور معارف سے بھرا
ہوا ہو.تو ایسے مضمون کے لکھنے میں وہی شخص سب سے اول درجہ پر رہے گا.کہ جو علمی طاقتوں
اور وسعت معلومات اور عام واقفیت اور ملکہ علوم دقیقہ میں سب سے اعلیٰ اور مشق اور ورزش
املاء وانشاء میں سب سے زیادہ تر فرسودہ روزگار ہو اور ہرگز ممکن نہ ہوگا کہ جو شخص اس سے
استعداد میں علم میں ، لیاقت میں، ملکہ میں، ذہن میں عقل میں کہیں فروتر اور منزل ہے.وہ
اپنی تحریر میں من حیث الکمالات اس سے برابر ہو جائے.مثلاً ایک طبیب حاذق جو علم ابدان
میں مہارت تامہ رکھتا ہے.جس کو زمانہ دراز کی مشق کے باعث سے تشخیص امراض اور تحقیق
Page 245
قرآن کریم میں تحریف کے الزامات کے جواب
229
عوارض کی پوری پوری واقفیت حاصل ہے اور علاوہ اس کے فن سخن میں بھی یکتا ہے اور نظم اور نثر
میں سرآمد روزگار ہے.جیسے وہ ایک مرض کے حدوث کی کیفیت اس کے علامات اور اسباب
فصیح اور وسیع تقریر میں بکمال صحت و حقانیت اور یہ نہایت متانت و بلاغت بیان کرسکتا ہے.اس کے مقابلے پر کوئی دوسرا شخص جس کو فن طبابت سے ایک ذرہ مس نہیں اور فن سخن کی
نزاکتوں سے بھی نا آشنا محض ہے.ممکن نہیں کہ مثل اس کے بیان کر سکے.یہ بات بہت ہی
ظاہر اور عام فہم ہے کہ جاہل اور عاقل کی تقریر میں ضرور کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے اور جس قدر
انسان کمالات علمیہ رکھتا ہے.وہ کمالات ضرور اس کی علمی تقریر میں اس طرح پر نظر آتے
ہیں.جیسے ایک آئینہ صاف میں چہرہ نظر آتا ہے اور حق اور حکمت کے بیان کرنے کے وقت وہ
الفاظ کہ جو اس کے مونہہ سے نکلتے ہیں.اس کی لیاقت علمی کا اندازہ معلوم کرنے کے لیے ایک
پیمانہ تصور کیے جاتے ہیں اور جو بات وسعت علم اور کمال عقل کے چشمہ سے نکلتی ہے اور جو
بات تنگ اور منقبض اور تاریک اور محدود خیال سے پیدا ہوتی ہے.ان دونوں طور کی باتوں میں
اس قدر فرق واضح ہوتا ہے کہ جیسے قوت شامہ کے آگے بشرطیکہ کسی فطرتی یا عارضی آفت سے
ماؤف نہ ہو.خوشبو اور بد بو میں فرق واضح ہے.جہاں تک تم چاہو فکر کرلو اور جس حد تک چاہو
سوچ لو کوئی خامی اس صداقت میں نہیں پاؤ گے اور کسی طرف سے کوئی رخنہ نہیں دیکھو گے پس
جبکہ من کل الوجوہ ثابت ہے کہ جو فرق علمی اور عقلی طاقتوں میں مخفی ہوتا ہے.وہ ضرور کلام میں
ظاہر ہو جاتا ہے اور ہرگز ممکن ہی نہیں کہ جو لوگ من حیث العقل والعلم افضل اور اعلیٰ ہیں وہ
فصاحت بیانی اور رفعت معانی میں یکساں ہو جائیں اور کچھ مابہ الامتیاز باقی نہ رہے.تو اس
صداقت کا ثابت ہونا اس دوسری صداقت کے ثبوت کو ستلزم ہے کہ جو کلام خدا کلام ہو.اس کا
انسانی کلام سے اپنے ظاہری اور باطنی کمالات میں برتر اور اعلیٰ اور عدیم المثال ہونا ضروری
ہے.کیونکہ خدا کے علم تام سے کسی کا علم برابر نہیں ہوسکتا اور اسی کی طرف خدا نے بھی اشارہ فرما
کر کہا ہے.فَاِلَّمْ يَسْتَجِيْبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ الله - الجزو نمبر
۱۲ [هود: 15] یعنی اگر کفار اس قرآن کی نظیر پیش نہ کر سکیں اور مقابلہ کرنے سے عاجز
رہیں.تو تم جان لو کہ یہ کلام علم انسان سے نہیں بلکہ خدا کے علم سے نازل ہوا ہے.جس کے علم
وسیع اور تام کے مقابلہ پر علوم انسانیہ بے حقیقت اور پیچ ہیں.اس آیت میں برہان انی کی طرز
پر اثر کے وجود کو مؤثر کے وجود کی دلیل ٹھہرائی ہے جس کا دوسرے لفظوں میں خلاصہ مطلب یہ
Page 246
الذكر المحفوظ
230
ہے کہ علم الہی بوجہ اپنی کمالیت اور جامعیت کے ہرگز انسان کے ناقص علم سے متشابہ نہیں
ہوسکتا.بلکہ ضرور ہے کہ جو کلام اس کامل اور بے مثل علم سے نکلا ہے.وہ بھی کامل اور بے مثل
ہی ہے اور انسانی کلاموں سے بکلی امتیاز رکھتا ہو.سو یہی کمالیت قرآن شریف میں ثابت
66
ہے.غرض خدا کے کلام کا انسان کے کلام سے ایسا فرق بین چاہیئے.“
براہین احمدیہ روحانی خزائن جلد اول صہ 214 تا240 ایڈیشن اول صہ 197 تا 214)
قرآن کریم کے چیلنج کی مزید وضاحت کرتے ہوئے حضرت
مسیح پاک فرماتے ہیں:
یہ امر ہر یک عاقل کے نزدیک بغیر کسی تردد اور توقف کے مسلم الثبوت ہے کہ گلاب کا
پھول بھی مثل اور مصنوعات الہیہ کے ایسی عمدہ خوبیاں اپنی ذات میں جمع رکھتا ہے جن کی مثل
بنانے پر انسان قادر نہیں اور وہ دو طور کی خوبیاں ہیں.ایک وہ کہ جو اس کی ظاہری صورت میں
پائی جاتی ہیں اور وہ یہ ہیں کہ اس کا رنگ نہایت خوشنما اور خوب ہے اور اس کی خوشبو نہایت
دلا رام اور دلکش ہے اور اس کے ظاہر بدن میں نہایت درجہ کی ملائمت اور تر و تازگی اور نرمی اور
نزاکت اور صفائی ہے.اور دوسری وہ خوبیاں ہیں کہ جو باطنی طور پر حکیم مطلق نے اس میں
ڈال رکھی ہیں یعنی وہ خواص کہ جو اس کے جوہر میں پوشیدہ ہیں اور وہ یہ ہیں کہ وہ مفرح اور
مقوی قلب اور مسکن صفرا ہے.اور تمام قومی اور ارواح کو تقویت بخشتا ہے اور صفر اور بلغم رقیق کا
مسہل بھی ہے اور اسی طرح معدہ اور جگر اور گردہ اور امعا اور رحم اور پھیپھڑہ کو بھی قوت بخشتا
ہے.اور خفقان حار اور غشی اور ضعف قلب کے لئے نہایت مفید ہے اور اسی طرح اور کئی
امراض بدنی کو فائدہ مند ہے.پس انہیں دونوں طور کی خوبیوں کی وجہ سے اس کی نسبت اعتقاد
کیا گیا ہے کہ وہ ایسے مرتبہ کمال پر واقعہ ہے کہ ہر گز کسی انسان کے لئے ممکن نہیں کہ اپنی طرف
سے کوئی ایسا پھول بناوے کہ جو اس پھول کی طرح رنگ میں خوشنما اور خوشبو میں دلکش اور بدن
میں نہایت تروتازہ اور نرم اور نازک اور مصفا ہو.اور باوجود اس کے باطنی طور پر تمام وہ
خواص بھی رکھتا ہو جو گلاب کے پھول میں پائے جاتے ہیں.اور اگر یہ سوال کیا جائے کہ کیوں
گلاب کے پھول کی نسبت ایسا اعتقاد کیا گیا کہ انسانی قوتیں اس کی نظیر بنانے سے عاجز ہیں
اور کیوں جائز نہیں کہ کوئی انسان اس کی نظیر بنا سکے.اور جو خوبیاں اس کی ظاہر و باطن میں پائی
جاتی ہیں وہ مصنوعی پھول میں پیدا کر سکے.تو اس سوال کا جواب یہی ہے کہ ایسا پھول بنانا
عادتا تمنع ہے اور آج تک کوئی حکیم اور فیلسوف کسی ایسی ترکیب سے
کسی قسم کی ادویہ کو ہم نہیں
Page 247
قرآن کریم میں تحریف کے الزامات کے جواب
231
پہنچا سکا کہ جن کے باہم مخلوط اور ممزوج کرنے سے ظاہر و باطن میں گلاب کے پھول کی سی
صورت اور سیرت پیدا ہو جائے.اب سمجھنا چاہیے کہ یہی وجوہ بے نظیری کی سورۃ فاتحہ میں بلکہ
قرآن شریف کے ہر یک حصہ اقل قلیل میں کہ جو چار آبہت سے بھی کم ہو.پائی جاتی ہیں.پہلے ظاہری صورت پر نظر ڈال کر دیکھو کہ کیسی رنگینی عبارت اور خوش بیانی اور جودت الفاظ اور
کلام میں کمال سلاست اور نرمی اور روانگی اور آب و تاب اور لطافت وغیرہ لوازم حسن کلام اپنا
کامل جلوہ دکھا رہے ہیں.ایسا جلوہ کہ جس پر زیادت متصور نہیں.اور وحشت کلمات اور تعقید
ترکیبات سے بکلی سالم اور بری ہے.ہر یک فقرہ اس کا نہایت فصیح اور بلیغ ہے اور ہر یک
ترکیب اس کی اپنے اپنے موقعہ پر واقعہ ہے اور ہر یک قسم کا التزام جس سے حسن کلام بڑھتا
ہے اور لطافت عبارت کھلتی ہے.سب اس میں پایا جاتا ہے.اور جس قدرحسن تقریر کے لئے
بلاغت اور خوش بیانی کا اعلیٰ سے درجہ ذہن میں آسکتا ہے وہ کامل طور پر اس میں موجود اور
مشہود ہے.اور جس قدر مطلب کے دل نشین کرنے کے لئے حسن بیان درکار ہے وہ سب اس
میں مہیا اور موجود ہے اور باوجود اس بلاغت معانی اور التزام کمالیت حسن بیان کے صدق اور
راستی کی خوشبو سے بھرا ہوا ہے.کوئی مبالغہ ایسا نہیں جس میں جھوٹ کی ذرا آمیزش ہو.کوئی
رنگینی عبارت اس قسم کی نہیں جس میں شاعروں کی طرح جھوٹ اور ہنرل اور فضول گوئی کی
نجاست اور بد بو سے مدد لی گئی ہو.پس جیسے شاعروں کا کلام جھوٹ اور ہنرل اور فضول گوئی کی
بد بو سے بھرا ہوا ہوتا ہے.یہ کلام صداقت اور راستی کی لطیف خوشبو سے بھرا ہوا ہے.اور پھر
اس خوشبو کے ساتھ خوش بیانی اور جودت الفاظ اور رنگینی اور صفائی عبارت کو ایسا جمع کیا گیا ہے
کہ جیسے گلاب کے پھول میں خوشبو کے ساتھ اس کی خوش رنگی اور صفائی بھی جمع ہوتی ہے.یہ
خوبیاں
تو باعتبار ظاہر کے ہیں.اور باعتبار باطن کے اس میں یعنی سورۃ فاتحہ میں یہ خواص ہیں
کہ وہ بڑی بڑی امراض روحانی کے علاج پر مشتمل ہے اور تکمیل قوت علمی اور عملی کے لئے بہت
سا سامان اس میں موجود ہے اور بڑے بڑے باڑوں کی اصلاح کرتی ہے اور بڑے بڑے
معارف اور دقائق اور لطائف کہ جو حکیموں اور فلسفیوں کی نظر سے چھپے رہے.اس میں مذکور
ہیں.سالک کے دل کو اس کے پڑھنے سے یقینی قوت بڑھتی ہے اور شک اور شبہ اور ضلالت کی
بیماری سے شفا حاصل ہوتی ہے.اور بہت سی اعلیٰ درجہ کی صداقتیں اور نہایت باریک حقیقتیں
کہ جو تکمیل نفس ناطقہ کے لئے ضروری ہیں.اس کے مبارک مضمون میں بھری ہوئی ہیں.اور
Page 248
الذكر المحفوظ
232
ظاہر ہے کہ یہ کمالات بھی ایسے ہیں کہ گلاب کے پھول کے کمالات کی طرح ان میں بھی عادتاً
ممتنع معلوم ہوتا ہے کہ وہ کسی انسان کے کلام میں مجتمع ہوسکیں.اور یہ امتناع نہ نظری بلکہ بدیہی
ہے.کیونکہ جن دقائق و معارف عالیہ کو خدائے تعالیٰ نے مین ضرورت حقہ کے وقت اپنے بلیغ
اور فصیح کلام میں بیان فرما کر ظاہری اور باطنی خوبی کا کمال دکھلایا ہے اور بڑی نازک شرطوں
کے ساتھ دونوں پہلوؤں ظاہر و باطن کو کمالیت کے اعلیٰ مرتبہ تک پہنچایا ہے.یعنی اول تو ایسے
معارف عالیہ ضرور یہ لکھے ہیں کہ جن کے آثار پہلی تعلیموں سے مندرس اور محو ہو گئے تھے اور
کسی حکیم یا فیلسوف نے بھی ان معارف عالیہ پر قدم نہیں مارا تھا.اور پھر ان معارف کو غیر
ضروری اور فضول طور پر نہیں لکھا بلکہ ٹھیک ٹھیک اس وقت اور اس زمانہ میں ان کو بیان فرمایا
جس وقت حالت موجودہ زمانہ کی اصلاح کے لئے ان کا بیان کرنا از بس ضروری تھا اور بغیر ان
کے بیان کرنے کے زمانہ کی ہلاکت اور تباہی متصور تھی.اور پھر وہ معارف عالیہ ناقص اور
نا تمام طور پر نہیں لکھے گئے بلکہ کما و کیفاً کامل درجہ پر واقعہ ہیں اور کسی عاقل کی عقل کوئی ایسی
دینی صداقت پیش نہیں کر سکتی جو ان سے باہر رہ گئی ہو.اور کسی باطل پرست کا کوئی ایسا وسوسہ
نہیں جس کا ازالہ اس کلام میں موجود نہ ہو.ان تمام حقائق و دقائق کے التزام سے کہ جو
دوسری طرف ضرورات حقہ کے التزام کے ساتھ وابستہ ہیں فصاحت بلاغت کے ان اعلیٰ
کمالات کو ادا کرنا جن پر زیادت متصور نہ ہو.یہ تو نہایت بڑا کام ہے کہ جو بشری طاقتوں سے
یہ بداہت نظر بلند تر ہے.( براہین احمدیہ جلد چہارم حاشیہ نمبر گیارہ روحانی خزائن جلد اول صفحہ 399-396 ایڈیشن اول
نیز فرمایا:
صفحہ 335-332 )
نیز اس بات کو بخوبی یا درکھنا چاہیئے.کہ قرآن شریف کا اپنی کلام میں بے مثل و مانند ہونا
صرف عقلی دلائل میں محصور نہیں بلکہ زمانہ دراز کا تجربہ صیحہ بھی اس کا مؤید اور مصدق ہے.کیونکہ باوجود اس کے کہ قرآن شریف برابر تیرہ سو برس سے اپنی تمام خوبیاں پیش کر کے
هل من معارض کا نقارہ بجا رہا ہے اور تمام دنیا کو بآواز بلند کہ رہا ہے کہ وہ اپنی ظاہری
صورت اور باطنی خواص میں بے مثل و مانند ہے اور کسی جن یا انس کو اس کے مقابلہ یا معارضہ
کی طاقت نہیں.مگر پھر بھی کسی متنفس نے اس کے مقابلہ پر دم نہیں مارا.بلکہ اس کی کم سے کم
کسی سورۃ مثلاً سورۃ فاتحہ کی ظاہری و باطنی خوبیوں کا بھی مقابلہ نہیں کر سکا.تو دیکھو اس سے
Page 249
233
قرآن کریم میں تحریف کے الزامات کے جواب
زیادہ بدیہی اور کھلا کھلے معجزہ اور کیا ہوگا.کہ عقلی طور پر بھی اس پاک کلام کا بشری طاقتوں
سے بلند تر ہونا ثابت ہوتا ہے اور زمانہ دراز کا تجربہ بھی اس کے مرتبہ اعجاز پر گواہی دیتا ہے
اور اگر کسی کو یہ دونوں طور کی گواہی کہ جو عقل اور تجربہ زمانہ دراز کے رو سے به پایہ ثبوت پہنچ
چکی ہے نا منظور ہو اور اپنے علم اور ہنر پر نازاں ہو.یا دنیا میں کسی ایسے بشر کی انشا پردازی کا
قائل ہو.کہ جو قرآن شریف کی طرح کوئی کلام بنا سکتا ہے.تو ہم جیسا کہ وعدہ کر چکے ہیں.کچھ بطور نمونہ حقائق دقائق سورۃ فاتحہ کے لکھتے ہیں.اس کو چاہیے کہ بمقابلہ ان ظاہری و
باطنى سورۃ فاتحہ کی خوبیوں کے کوئی اپنا کلام پیش کرے.....اور اگر کوئی اس امر کو تسلیم نہ
کرے.تو یہ بار ثبوت اسی کی گردن پر ہے کہ وہ آپ یا کسی اپنے مددگار سے عبارت قرآن
کی مثل بنوا کر پیش کرے.مثلاً سورۃ فاتحہ کے مضمون کو لیکر کوئی دوسری فصیح عبارت بنا کر
دکھلا دے جو کمال بلاغت اور فصاحت میں اس کے برابر ہو سکے.اور جب تک ایسا نہ
کرے.تب تک وہ ثبوت کہ جو مخالفین کے تیرہ سو برس خاموش اور لا جواب رہنے سے اہل
حق کے ہاتھ میں ہے.کسی طور سے ضعیف الاعتبار نہیں ہوسکتا.بلکہ مخالفین کے سینکڑوں
برسوں کی خاموشی اور لاجواب رہنے نے اس کو وہ کامل مرتبہ ثبوت کا بخشا ہے کہ جو گلاب
کے پھول وغیرہ کو وہ ثبوت بے نظیری کا حاصل نہیں.کیونکہ دنیا کے حکیموں اور صنعت کاروں
کو کسی دوسری چیز میں اس طور پر معارضہ کے لئے کبھی ترغیب نہیں دی گئی اور نہ اس کی مثل
بنانے سے عاجز رہنے کی حالت میں
کبھی ان کو یہ خوف دلایا گیا کہ وہ طرح طرح کی تباہی
اور ہلاکت میں ڈالے جائیں گے.براہین احمدیہ جلد چہارم حاشیہ نمبر گیارہ روحانی خزائن جلد اول صفحہ 404-402 ایڈیشن اول
صفحه 338 )
دوسرے نشان صدق یہ کہ ہر یک صداقت دینی کو وہ بیان کرتا ہے اور تمام وہ امور بتلاتا ہے
کہ جو ہدایت کامل پانے کے لیے ضروری ہیں اور یہ اس لیے نشان صدق ٹھہرا کہ انسان کی
طاقت سے یہ بات باہر ہے کہ اس کا علم ایسا وسیع و محیط ہو جس سے کوئی دینی صداقت وحقائق
دقیقہ بار نہ رہیں.غرض ان تمام آیات میں خدائے تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ قرآن شریف
ساری صداقتوں کا جامع ہے اور یہی بزرگ دلیل اس کی حقانیت پر ہے اور اس دعوی پر صدہا
برس بھی گزرر گئے.پر آج تک کسی برہمو وغیرہ نے اس کے مقابلے پر دم بھی نہ مارا.تو اس
صورت میں ظاہر ہے کہ بغیر پیش کرنے کسی ایسی جدید صداقت کے کہ جو قرآن شریف سے باہر
Page 250
الذكر المحفوظ
234
رہ گئی ہو.یونہی دیوانوں اور سودائیوں کی طرح اوہام باطلہ پیش کرنا جن کی کچھ بھی اصلیت
نہیں.اس بات پر پختہ دلیل ہے کہ ایسے لوگوں کو راست بازوں کی طرح حق کا تلاش کرنا منظور
ہی نہیں.بلکہ نفس امارہ کو خوش رکھنے کے لیے اس فکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ کسی طرح خدا کے
پاک احکام سے بلکہ خدا ہی سے آزادگی حاصل کر لیں.اسی آزادگی کے حصول کی غرض سے خدا
کی سچی کتاب سے جس کی حقانیت اظہر من الشمس ہے ایسے منحرف ہورہے ہیں کہ نہ متکلم بن کر
شائستہ طریق پر کلام کرتے ہیں اور نہ سامع ہونے کی حالت میں کسی دوسرے کی بات سنتے
ہیں.بھلا کوئی ان سے پوچھے کہ کب کسی نے کوئی صداقت دینی قرآن کے مقابلہ پر پیش کی
جس کا قرآن نے کچھ جواب نہ دیا اور خالی ہاتھ بھیج دیا جس حالت میں تیرہ سو برس سے قرآن
شریف باواز بلند دعوی کر رہا ہے کہ تمام دینی صداقتیں اس میں بھری پڑی ہیں.تو پھر یہ کیسا
خبث طینت ہے کہ امتحان کے بغیر ایسی عالیشان کتاب کو ناقص خیال کیا جائے اور یہ کس قسم کا
مکابرہ ہے کہ نہ قرآن شریف کے بیان کو قبول کریں اور نہ اس کے دعوی کو توڑ کر دکھلائیں.سچ تو
یہ ہے کہ ان لوگوں کے لبوں پر تو ضرور کبھی کبھی خدا کا ذکر آ جاتا ہے.مگر ان کے دل دنیا کی گندگی
سے بھرے ہوئے ہیں.اگر کوئی دینی بحث شروع بھی کریں تو اس
کو مکمل طور پر ختم کرتا نہیں
چاہتے.بلکہ نا تمام گفتگو کا ہی جلدی سے گلا گھوٹ دیتے ہیں.تا ایسا نہ ہو کہ کوئی صداقت ظاہر
ہو جائے اور پھر بے شرمی یہ کہ گھر میں بیٹھ کر اس کامل کتاب کو ناقص بیان کرتے ہیں.جس نے
بوضاحت تمام فرما دیا.الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ
نِعْمَتِي الجزو نمبر ۶ [المائدہ: 4] یعنی آج میں نے اس کتاب کے نازل کرنے سے
علم دین کو مرتبہ کمال تک پہنچا دیا اور اپنی تمام نعمتیں ایمانداری پر پوری کر دیں.اے حضرات!
کیا تمہیں کچھ بھی خدا کا خوف نہیں؟ کیا تم ہمیشہ اسی طرح جیتے رہو گے؟ کیا ایک دن خدا کے
حضور میں اس جھوٹے منہ پر لعنتیں نہیں پڑیں گی ؟ اگر آپ لوگ کوئی بھاری صداقت لیے بیٹھے
ہیں جس کی نسبت تمہارا یہ خیال ہے کہ ہم نے کمال جانفشانی اور عرق ریزی اور موشگانی سے اس
کو پیدا کیا ہے اور جو تمہارے گمان باطل میں قرآن شریف اس صداقت کے بیان کرنے سے
قاصر ہے تو تمہیں قسم ہے کہ سب کا روبار چھوڑ کر وہ صداقت ہمارے رو برو پیش کرو.تا ہم تم کو
قرآن شریف میں سے نکال کر دکھلا دیں.مگر پھر مسلمان ہونے پر مستعد رہو اور اگر اب بھی
آپ بدگمانی اور بک بک کرنا نہ چھوڑیں اور مناظرہ کا سیدھا راستہ اختیار نہ کریں.تو بجز اس کے
Page 251
قرآن کریم میں تحریف کے الزامات کے جواب
235
اور کیا کہیں کہ لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ [آل عمران:62]
براہین احمدیہ جلد چہارم حاشیه گیاره روحانی خزائن جلد اول صفحہ 226,227 ایڈیشن اول صفحہ 206 )
ہر یک باخبر آدمی پر ظاہر ہے کہ مخالفین باوجو دسخت حرص اور شدت عناد اور پرلے درجہ کی
مخالفت اور عداوت کے مقابلہ اور معارضہ سے قدیم سے عاجز رہے ہیں.اور اب بھی عاجز ہیں
اور کسی کو دم مارے کی جگہ نہیں.اور باوجود اس بات کے کہ اس مقابلہ سے ان کا عاجز رہنا ان کو
ذلیل بناتا ہے.جہنمی ٹھہراتا ہے.کافر اور بے ایمان کا ان کو لقب دیتا ہے.بے حیا اور بے شرم.ان کا نام رکھتا ہے.مگر مردہ کی طرح ان کے مونہہ سے کوئی آواز نہیں نکلتی.پس لا جواب رہنے
کی ساری ذلتوں کو قبول کرنا اور تمام ذلیل ناموں کو اپنے لئے روا رکھنا اور تمام قسم کی بے حیائی
اور بے شرمی کی خس و خاشاک کو اپنے سر پر اٹھا لینا اس بات پر نہایت روشن دلیل ہے کہ ان
ذلیل چمگادڑوں کی اس آفتاب حقیقت کے آگے کچھ پیش نہیں جاتی.پس جبکہ اس آفتاب
صداقت کی اس قدر تیز شعاعیں چاروں طرف سے چھوٹ رہی ہیں کہ ان کے سامنے ہمارے
دشمن خفاش سیرت اندھے ہورہے ہیں.تو اس صورت میں یہ بالکل مکابرہ اور سخت جہالت ہے
کہ گلاب کے پھول کی خوبیوں کو کہ جو بہ نسبت قرآنی خوبیوں کے ضعیف اور کمزور اور قلیل
الثبوت ہیں.اس مرتبہ بے نظیری پر سمجھا جائے کہ انسانی قوتیں ان کی مثل بنانے سے عاجز
ہیں.مگر ان اعلیٰ درجہ کی خوبیوں کو کہ جو کئی درجہ گلاب کے پھول کی ظاہری و باطنی خوبیوں سے
افضل و بہتر اور قوی الثبوت ہیں.ایسا خیال کیا جائے کہ گویا انسان ان
کی نظیر بنانے پر قادر ہے.براہین احمدیہ جلد چہارم حاشیہ نمبر گیارہ روحانی خزائن جلد اول صفحہ 1412 ایڈیشن اول صفحہ 346 )
پس اگر ا بن و راق کو اپنی جہالت کی وجہ سے یہ حسن نظر نہیں آتا اور نہ ہی عقل سے کام لیتا ہے کہ ایک عرب فصیح
البیان، قادر الکلام شخص کے بارہ میں کہا جاتا ہے کہ وہ ترتیب لگا تا تھا اس لیے لازماً کلام کسی اسلوب پر ہی مرتب کیا گیا
ہوگا، تو اس کے لیے ایک اور طریق ہے کہ قرآن کریم کے اس چیلنج کو قبول کرے اور مقابلہ کے لیے میدان میں اُترے.سوال یہ ہے کہ جہاں تک قرآن کریم کے اسلوب بیان
کا تعلق ہے تو اہل علم بر ما گواہی دیتے ہیں کہ قرآن کریم کا
اسلوب بیان اپنے حسن و جمال میں عالی شان، بے مثل اور اہل کمال کے اسلوب سے اعلیٰ وارفع ہے.مگر وہ اسلوب
ہے کیا ؟ عام شخص کو، جو عربی زبان سے واقف نہیں یا قرآن کریم کا گہرا مطالعہ نہیں رکھتا، کس طرح سمجھایا جائے؟
Page 252
الذكر المحفوظ
236
قرآن کریم کی معنوی ترتیب اور اس کا دستور بیان
تمام مذاہب کے قیام کا بنیادی مقصد دراصل تقویٰ پیدا کرنا ہے.اسلام بھی اسی مقصد کی خاطر آیا اور اس
وقت آیا جب کہ تمام مذاہب مختلف وجوہات سے اس مقصد کو حاصل کرنے میں نا کام ہو چکے تھے.حضرت مرزا
غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی معہود علیہ السلام فرماتے ہیں:
پھر دیکھو کہ تقویٰ ایسی اعلیٰ درجہ کی ضروری شے قرار دیا گیا ہے کہ قرآن کریم کی علت غائی
اسی کو ٹھہرایا ہے چنانچہ دوسری سورۃ کو جب شروع کیا ہے تو یوں ہی فرمایا ہے: الم ذلک
الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ (البقره: 3-2 )
( ملفوظات جلد اول صفحه 282)
اور تقویٰ پیدا کرنے کے لیے سب سے بنیادی امر عبادت الہی ہے.چنانچہ قرآن کریم کا پہلا حکم جو امر کے
صیغہ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ تقویٰ کے قیام کے خاطر خدا تعالیٰ کی عبادت کرو.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:
يَايُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ
تتقون (البقرة : 22)
ترجمہ: اے لوگو! تم عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان کو بھی جو تم سے
پہلے تھے تا کہ تم تقویٰ اختیار کرو.پس اس آیت میں قرآن کریم ایسی عبادت الہی کو انسانی پیدائش کا مقصود بیان کرتا ہے جس عبادت سے تقویٰ
( ملفوظات جلد اول صفحہ 246,347)
پیدا ہو.حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی معہود علیہ السلام فرماتے ہیں:
اس قدر تفاصیل جو ( قرآن مجید میں ) بیان کی جاتی ہیں ان کا خلاصہ اور مغز کیا ہے ؟ الا
تَعْبُدُوا إِلَّا الله [هود : 2] خدا تعالیٰ کے سوا ہر گز ہر گز کسی کی پرستش نہ کرو.اصل بات یہ ہے
کہ انسان کی پیدائش کی علت غائی یہی عبادت ہے جیسے دوسری جگہ فرمایا ہے وَ مَا خَلَقْتُ
الجنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ [الذاريت : 57]
اور عبادت الہی اور تقویٰ کا قیام کامل توحید کے قیام کے بغیر ناممکن ہے اس لیے توحید الہی کا قیام بھی قرآن
کریم کے نزول کی علت غائی ٹھہرا.حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی معہود علیہ السلام فرماتے ہیں:
تمام احکام ایک ہی مرکز کے گرد گھوم رہے ہیں یعنی علمی اور عملی رنگ میں اور درشتی اور نرمی
کے پیرایہ میں خدا کی توحید پر قائم کرنا اور ہوا و ہوس چھوڑ کر خدا کی توحید کی طرف کھینچنا یہی
قرآن کا مدعا ہے.چشمه معرفت: روحانی خزائن جلد 23 صفحہ 198 )
Page 253
قرآن کریم میں تحریف کے الزامات کے جواب
237
پس تو حید الہی اور عبادت الہی اور تقویٰ قرآن کریم کے نزول کا مقصد ہیں.قرآن کریم کی ظاہری ترتیب، اس کی معنوی ترتیب سمجھنے کے لیے ظاہری ترتیب کی اہمیت اور مقصد نزول کی
وضاحت کے بعد قرآن کریم کی معنوی ترتیب اور اس کے دستور بیان کو سمجھنا آسان ہوگا.قرآن کریم کا اسلوب بیان بطریق درس و تعلیم
اللہ تعالیٰ نے نزول قرآن کریم کے مقصد کے حصول کے لیے جو اسلوب اپنایا ہے اسے درس سے تشبیہ دی
ہے.فرماتا ہے:
وَ كَذلِكَ نُصَرِفُ الآيَتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَنَّهُ لِقَوْمٍ
يَعْلَمُونَ: (الانعام: 106)
اور اسی طرح ہم نشانات کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں تا کہ وہ کہہ اٹھیں کہ تو نے خوب سیکھا
اور خوب سکھایا اور تا کہ ہم صاحب علم لوگوں پر اس ( مضمون ) کو خوب روشن کر دیں.پس قرآن کریم ایک تعلیم بھی ہے اور درس بھی.اس میں ہر ضروری مضمون اپنی تمام تر جزئیات کے ساتھ مکمل
وضاحت سے کھول کھول کر بیان کر دیا گیا ہے اور مقصد یہ ہے کہ مضمون کو امثال اور واقعات کی روشنی میں تاریخی
اور فطرتی شہادات سے سجا کر اس طرح پیش کیا جائے کہ وہ قاری اور سامع کی علمی، روحانی اور ذوقی تسکین کے
ساتھ ساتھ اس کے دل میں بھی ثبت ہوتا چلا جائے.پس قرآن کریم میں بیان شدہ کسی بھی مضمون کی جزئیات کو
ایک درس کے طور پر بار بار مختلف پیرائے میں دہرا کر اور مختلف انداز سے اس طرح بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ
اس کے مضامین طالب کے دل و دماغ میں راسخ ہوتے چلے جائیں.حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و
مہدی معہود علیہ السلام فرماتے ہیں:
خدا کا فصیح کلام معارف حقہ کو کمال ایجاز سے، کمال ترتیب سے، کمال صفائی اور خوش بیانی
سے لکھتا ہے اور وہ طریق اختیار کرتا ہے جس سے دلوں پر اعلیٰ درجہ کا اثر پڑے اور تھوڑی عبارت
میں وہ علوم الہیہ سا جائیں جن پر دنیا کی ابتدا سے کسی کتاب یا دفتر نے احاطہ نہیں کیا.یہی حقیقی
فصاحت بلاغت ہے جو تکمیل نفس انسانی کے لیے ممدو معاون ہے جس کے ذریعہ سے حق کے
طالب کمال مطلوب تک پہنچتے ہیں اور یہی وہ صفت ربانی ہے جس کا انجام پذیر ہونا بجز الہی
طاقت اور اس کے علم وسیع کے
ممکن نہیں.( براہین احمدیہ چہار حصص روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 466-464 حاشیہ نمبر 3)
Page 254
الذكر المحفوظ
238
اس مقصد کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو دستور و اسلوب بیان اپنایا ہے اس کی
وضاحت کرتے ہوئے اور قرآن کے بیان فرمودہ مضامین کی ترتیب کے بارہ میں سورۃ ھود میں فرماتا ہے:
ترجیب مضامین قرآن
الراكِتُبْ أَحْكِمَتْ ايتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ۖ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا
اللهُ إِنَّنِي لَكُمْ مِّنْهُ نَزِيرٌ وَ بَشِيرٌ - و أن اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ
يُمَتِّعُكُمْ مَّتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلِ فَضْلَهُ وَإِنْ
تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرِ.(آیات 2 تا4)
ترجمہ: ( یہ ) ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیات مستحکم بنائی گئی ہیں (اور ) پھر صاحب
حکمت (اور ) ہمیشہ خبر رکھنے والے کی طرف سے اچھی طرح کھول دی گئی ہیں.( متنبہ کر رہی
ہیں ) کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو.میں یقینا تمہارے لیے اس کی طرف سے ایک
نذیر اور ایک بشیر ہوں.نیز یہ کہ تم اپنے رب سے استغفار کرو پھر اس کی طرف تو بہ کرتے ہوئے
جھکو تو تمہیں وہ ایک مقررہ مدت تک بہترین سامانِ معیشت عطا کرے گا اور وہ ہر صاحب
فضیلت کو اس کے شایان شان فضل عطا کرے گا اور اگر تم پھر جاؤ تو یقینا میں تمہارے بارہ میں
ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں.ان آیات میں یہ مضمون ہے کہ خدائے حکیم و خبیر کی طرف سے قرآن کریم کی محکم آیات کے مضامین کی تفصیل
یہ ہے کہ مقصد اعلیٰ عبادت الہی کا قیام ہے چنانچہ اس مقصد کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کو
اسوہ حسنہ بناتے ہوئے ایسی کتاب کے ساتھ بھیجا ہے جس میں تمام ضروری مضامین انذار اور بشارت کے
پیرایہ میں بیان کیے گئے ہیں تا کہ طالب استغفار اور تو بہ کے پانی سے اپنے تقویٰ کی آبیاری کرے اور اس کے
نتیجہ میں الہی انعامات کا وارث بنے.مگر یہ سب ہر طالب کی ذاتی استعداد اور فضیلت کے مطابق ہوگا.جو اپنی
استعدادوں کے دائرہ میں رہتے ہوئے جتنا کمال حاصل کر لے گا اسی قدر وہ خدا کے فضلوں کا وارث ہوگا.اور
شرارت کرتے ہوئے جو پھرے گا تو وہ خدا کے غضب کا مورد ہو گا.پس ان آیات کے حوالہ سے قرآن کریم کے مضامین کی ایک ترتیب کچھ یوں معلوم ہوتی ہے کہ:
اول: اس کتاب اور تعلیم کا مقصود حصول تقومی کے لیے خدائے واحد کی عبادت کا قیام ہے.دوم: اس مقصد کے حصول کے لیے آنحضرت ﷺ کو تنبیہ کرنے والا اور بشارت دینے والا بنا کر بھیجا گیا ہے.سوم : آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اسوہ حسنہ اور کامل نمونہ سے اسلامی تعلیمات سکھائیں گے.
Page 255
قرآن کریم میں تحریف کے الزامات کے جواب
239
چهارم: یہ مشکل کام بجز خدا تعالیٰ کی توفیق کے نہیں ہوگا پس توفیق حاصل کرنے کے لیے استغفار کی تعلیم دی
اور عملی رنگ میں ڈھلنے کے لیے رسول کریم کی صحیح عملی پیروی کرنے کے لیے تو بہ کی تعلیم دی.پنجم: پس اپنی اپنی استعدادوں کے مطابق اس تعلیم پر عمل پیرا ہونے والے ایک خاص وقت کے بعد انعام واکرام
کے وارث ہوں گے اور اُن میں وہ لوگ بھی ہوں گے جو کامل پیروی اور اطاعت کرنے کی وجہ سے رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل ظل ہو نگے.ششم: جو اس تعلیم پر عمل پیرا نہ ہوں گے وہ ایک خاص وقت تک مہلت پانے کے بعد عذاب الہی کا مورد
ہوں گے.ان مضامین کے اسلوب بیان کے بارہ میں رہنمائی فرماتے ہوئے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود
و مہدی معہود علیہ السلام فرماتے ہیں:
سمجھنا چاہیے کہ قرآن شریف کی بلاغت ایک پاک اور مقدس بلاغت ہے.جس کا مقصد
اعلیٰ یہ ہے کہ حکمت اور راستی کی روشنی کو فصیح کلام میں بیان کر کے تمام حقائق اور دقائق علم دین
ایک موجز اور مدلل عبارت میں بھر دیئے جائیں.اور جہاں تفصیل کی اشد ضرورت ہو وہاں
تفصیل ہو اور جہاں اجمال کافی ہو وہاں اجمال ہو اور کوئی صداقت دینی ایسی نہ ہو جس کا مفصلا
یا مجملاً ذکر نہ کیا جائے اور باوصف اسکے ضرورت حقہ کے تقاضا سے ذکر ہو نہ غیر ضروری طور پر
اور پھر کلام بھی ایسا فصیح اور سلیس اور متین ہو کہ جس سے بہتر بنانا ہرگز کسی کیلئے ممکن نہ ہواور پھر وہ
کلام روحانی برکات بھی اپنے ہمراہ رکھتا ہو.یہی قرآن شریف کا دعوی ہے جس کو اس نے آپ
ثابت کر دیا ہے اور جابجا فرما بھی دیا ہے کہ کسی مخلوق کیلئے ممکن نہیں کہ اسکی نظیر بنا سکے.( براہین احمدیہ چہار صص روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 477-476 حاشیہ نمبر 3)
پس کلام الہی میں گہرے علمی اور فلسفیانہ دلائل کے بیان کا مقصد کیونکہ مناظرہ یا مباحثہ نہیں بلکہ درس و تدریس
اور تعلیم و تربیت ہے اور درس میں انداز بیان کتابی نہیں ہوتا بلکہ مدرس مضامین کی ترتیب کے بیان میں وہ انداز
اختیار کرتا ہے جس سے مضمون سامعین کے ذہن نشین بھی ہو جائے اور دلوں کو بھی تقویت دے.چنانچہ مدرس ایک
مضمون بیان کرتے ہوئے اس سے متعلقہ مضامین بیان کرتا ہے اور پھر مضمون واضح کرنے کے لیے اسے مختلف
انداز اور پیرائے میں دہرا کر بیان کرتا ہے اور راسخ کرنے کے لیے دلائل کے ساتھ ساتھ عبرت انگیز واقعات اور
خوبصورت محاوروں سے مضمون کو سجاتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ اس کا مضمون ہر طبیعت کے آدمی کی دلچپسی کا باعث
ہو اور ہر فطرت کا انسان اس سے فائدہ اُٹھائے.پھر تاریخی اور فطری دلائل کو اس طرح پیش کرتا ہے کہ کہ درس کے
Page 256
240
الذكر المحفوظ
اختام
پر مضمون کے تمام ضروری پہلوؤں کا احاطہ ہوچکا ہوتا ہے اور سُننے والوں کو اس مضمون پر تمام ضروری
معلومات حاصل ہو چکی ہوتی ہیں اور ساتھ ساتھ ذہن بھی اس کی حقانیت کو تسلیم کر چکے ہوتے ہیں اور دل بھی عمل
کرنے کے لیے تقویت پاچکے ہوتے ہیں.قرآن کریم بہترین انداز میں یہ طریق اختیار کرتا ہے پس اسے کلام کی
کمزوری کیونکر کہا جاسکتا ہے؟ یہ تو ایک ایسی خوبی ہے جس میں کوئی کتاب قرآن کریم کی ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتی.اپنے مقصد اعلیٰ یعنی تقوی کے حصول کے لیے اپنے اسلوب بیان کے بہترین ہونے کی اس خصوصیت کو
قرآن کریم ان الفاظ میں بیان کرتا ہے:
اللهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَبًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِي تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ
يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ
يَهْدِي بِهِ مَنْ يَّشَاءُ وَ مَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادٍ.(الزمر:24)
اللہ نے بہترین بیان ایک ملتی جلتی ( اور ) بار بارڈ ہرائی جانے والی کتاب کی صورت میں
اتارا ہے.جس سے ان لوگوں کی جلد میں جو اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں لرزنے لگتی ہیں پھر ان
کی جلد میں اور ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہوتے ہوئے ) نرم پڑ جاتے ہیں.یہ
اللہ کی ہدایت ہے ، وہ اس کے ذریعہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے اللہ گمراہ ٹھہرا دے تو
اُسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں.حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی معہود علیہ السلام فرماتے ہیں:
سورۃ فاتحہ اور قرآن شریف میں ایک اور خاصہ بزرگ پایا جاتا ہے کہ جو اسی کلام پاک سے
خاص ہے اور وہ یہ ہے کہ اس کو توجہ اور اخلاص سے پڑھنا دل کو صاف کرتا ہے اور ظلمانی پر دوں کو
اٹھاتا ہے اور سینے کو منتشرح کرتا ہے اور طالب حق کو حضرت احدیت کی طرف کھینچ کر ایسے انوار
اور آثار کا مورد کرتا ہے کہ جو مقربانِ حضرت احدیت میں ہونی چاہیے اور جن کو انسان کسی
دوسرے حیلہ یا تدبیر سے ہرگز حاصل نہیں کر سکتا اور اس روحانی تا ثیر کا ثبوت بھی ہم اس کتاب
میں دے چکے ہیں اور اگر کوئی طالب حق ہو.تو بالمواجہ ہم اس کی تسلی کر سکتے ہیں اور ہر وقت تازہ
بتازہ ثبوت دینے کو طیار ہیں.براہین احمدیہ چہار حص حاشیہ نمبر گیارہ روحانی خزائن جلد اول صفحہ 402 ایڈیشن اول صفحہ 338)
قرآن کریم ایک مضمون بیان کرتے ہوئے فطرتِ انسانی کی طرف سے اُٹھنے والے تمام طبعی سوالات کے
جوابات بھی نہایت عمدہ پیرایہ میں ساتھ ساتھ دیتا جاتا ہے.کسی مضمون کے بیان میں جب ایسا موقع آتا ہے کہ
Page 257
قرآن کریم میں تحریف کے الزامات کے جواب
241
قاری کا یا سامع کا دل تقویٰ کی طرف مائل ہورہا ہوتا ہے تو اس وقت عقلی یا علمی دلائل سے ہٹ کر موضوع کا رُخ
اس سمت پھیرنا ضروری ہوتا ہے جس سے قاری یا سامع کا دل تقویت پائے اور تقویٰ میں ترقی ہو اور دلائل کے
سمجھنے نتیجہ میں صرف مبہوت اور لا جواب ہو کر نہ رہ جائے اور عبادت الہی کے لیے اس لیے راضی نہ ہو کہ اگر نہ کی تو
لوگوں کو کیا جواب دوں گا بلکہ ان مضامین کے بیان سے کتاب کے نزول کا مقصد اعلیٰ حاصل ہو یعنی تقویٰ کے
حصول کے لیے راہ ہموار ہواور قاری کا دل خدا کے حضور سجدہ ریز ہو جائے اور بلاخوف لومۃ لائم صرف خدا تعالیٰ کی
رضا اور خوشنودی کے لیے عبادت کی طرف توجہ کرے نہ کہ ماحول کے مطابق رویہ اختیار کرے.اس موقع پر کسی
بات کو دہرا کر اور نئے نئے انداز میں بیان
کرنا یا عفو درگزر کی کسی مثال کے ذکر کے بعد خدا تعالیٰ کی رحیمیت کی سے
قاری اور سامع کے دل کو گداز کرنا یا کسی عبرت آموز واقعہ کے بیان کے بعد خدا تعالیٰ کے کبر و جبروت کی طرف اس
انداز میں توجہ دلانا کہ بہت خداوندی کے ساتھ ساتھ محبت الہی بھی دلوں کو گرمائے ، تاکہ منافقت کی جڑ مر جائے،
تقویٰ کا بیج دل میں بویا جائے اور ریا کاری کی بجائے اخلاص اور محبت سے روح آستانہ الوہیت پر پانی کی طرح
بہنے لگے.یا پھر ایک تاریخی واقعہ سے خدا تعالیٰ کی متعلقہ صفات کی طرف قاری کی توجہ مبذول کرانا ہی دراصل کلام
الہی کا اندرونی ربط ہو گا اور اس ربط کو چھوڑنا، مقصد اعلیٰ سے دُور ہونے کے برابر ہوگا.پس ایسے موقع پر ایک ظاہری
ربط سے ہٹنا ہی دراصل کلام کو مربوط رکھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے.ایک خشک ملا اس موقع پر مقصد اعلیٰ کی طرف
نظر کیے بناہی اعتراض کر دے گا لیکن ایک ایسا قاری جو کتاب کے مقصد سے واقف ہے، عش عش کر اُٹھے گا.قرآن کریم کے اس اسلوب بیان کو فلپ کے حتی بھی سمجھتے ہیں.لکھتے ہیں:
All these narratives are used didactically, not for the
object of telling a story but to preach a moral, to teach
that God in former times has always rewarded the
righteous and punished the wicked
(History of Arabs Pg: 125)
قرآن کریم کا سارا بیان ایک درس کی صورت میں ہے جس کا مقصود محض قصہ گوئی نہیں بلکہ
اخلاقیات کی تعلیم دینا اور یہ سمجھانا ہےکہ اللہ تعالیٰ متقیوں کا ہمیشہ نوازتا اور بر وں کو سزا دیا کرتا ہے.قرآن کریم کا اسلوب بیان عام طرز پر نہیں ہے
جب کوئی شخص کتاب لکھتا ہے تو اپنے مبلغ علم کے مطابق اس کے عناوین مرتب کرتا ہے اور اپنے محدود علم
کے دائرہ میں رہتے ہوئے ان عناوین کے تحت ایک ترتیب کے ساتھ مضمون کی جزئیات بیان کرتا ہے.قاری کو
مصنف کے ایک عنوان کے تحت ملتے جلتے مضامین کو ذہن نشین کرنے میں زیادہ وقت نہیں ہوتی اور وہ اس کی
ترتیب کو آسانی سے سمجھ لیتا ہے بلکہ ساتھ ساتھ تجزیہ بھی کرتا جاتا ہے کہ مصنف نے مضامین کو بہترین رنگ میں
Page 258
الذكر المحفوظ
242
بیان کیا ہے یا مزید بہتری کی گنجائش موجود ہے.قرآن کریم کے الہی کلام ہونے کی وجہ سے اس کا انداز اور اسلوب بیان عام کتب جیسا نہیں ہے کیونکہ خدا
تعالیٰ کا مبلغ علم عام مصنفین کی طرح محدود تو نہیں ہے.اس لیے کتاب الہی میں جب کوئی بھی مضمون بیان ہو تو وہ
انسانی علم کی طرح محدود نہیں ہونا چاہیے بلکہ غیر محدود سر چشمہ علم سے پھوٹنے کی وجہ سے گہرائی اور وسعت
میں انسانی علم سے وسیع تر ، جامع اور کامل ہونا چاہیے.پس بنی نوع انسانی کی راہنمائی کے لیے نازل ہونے والی
خدا تعالیٰ کی کتاب میں اگر تمام ضروری مضامین کو الگ الگ بیان کیا جائے تو تمام مضامین پر مشتمل یہ کتاب بھی
غیر محدودضخامت کی حامل ہونی چاہیے.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:
قُل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادَ أَ لِكَلِمَتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَتُ
رَبّى وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا- (الكهف: 110)
ترجمہ: کہہ دے کہ اگر سمندر میرے رب کے کلمات کے لیے روشنائی بن جائیں تو سمندر
ضرورختم ہو جائیں گے پیشتر اس کے کہ میرے رب کے کلمات ختم ہوں خواہ ہم بطور مدد اس جیسے
اور (سمندر ) لے آئیں.حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی معہود علیہ السلام اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں:
اور اس میں ستر یہ ہے کہ جو چیز غیر محدود قدرت سے وجود پذیر ہوئی ہے اُس میں غیر محدود
عجائبات اور خواص کا پیدا ہونا ایک لازمی اور ضروری امر ہے اور یہ آیت کہ قُل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ
مِدَاداً لِكَلِمَتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا
اپنے ایک معنے کی رُو سے اسی امر کی مؤید ہے.کرامات الصادقین روحانی خزائن جلد 7 صفحہ 60)
پس جب خدا تعالیٰ کا کلام ہونے کی وجہ سے قرآن کریم کے معارف غیر محدود ہیں تو اگر یہ معارف عام
اسلوب اور دستور تحریر پر بیان کیے جاتے تو ہزار ہا جلدوں کی کتاب درکار تھی.یہ بات تو ظاہر ہے کہ محدود قومی رکھنے
والے بنی نوع کے لیے ایسی غیر محدود کتاب تو فائدہ مند نہیں ہو سکتی تھی.کیونکہ ہزار ہا اجزا کی کتاب کو سنبھالنا کسی
ایک انسان کے بس کی بات نہیں تھی کجا یہ کہ اسے پڑھا سمجھا اور حفظ کیا جاتا.پس خدا تعالیٰ کی کتاب
کی تقسیم و ترتیب
اور اسلوب بیان عام انسانی اسلوب بیان سے لازماً مختلف اور وسیع تر ہونا چاہیے.چنانچہ غیر محدود علوم کے بیان
کے لیے خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایسا انداز اپنایا جو کہ ایک عام انسان کی علمی ، جسمانی اور روحانی استعدادوں
کے مطابق بھی ہے اور غیر محدود علوم کو سمیٹے ہوئے بھی ہے تا کہ اس کتاب کا مطالعہ کرنے والا نزول قرآن سے لے
Page 259
قرآن کریم میں تحریف کے الزامات کے جواب
243
کر قیامت تک اسے ہر زمانہ اور ہر علاقہ اور ہر معاشرہ کے لیے ہر وقت مفید پائے.لہذا خدا تعالیٰ نے قرآن کریم
میں عام انسانی کتب کی طرح نہیں بلکہ اپنی قدرت کاملہ سے محدود الفاظ میں تمام ضروری مضامین اپنی تمام تر
تفصیلات کے ساتھ ایسے معجزانہ اسلوب میں بیان فرما دیے ہیں کہ ہر زمانہ کا انسان اپنے دور کی ضروریات اور علوم
کے مطابق ہدایت اخذ کرتا ہے.اس حقیقت کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں مختلف انداز میں بیان کرتا ہے.مثلاً :
لَا رَطْبٍ وَّ لَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينِ (الانعام: 60)
ترجمہ: کوئی تر یا خشک چیز نہیں مگر (اس کا ذکر ) اس روشن کتاب میں ہے.وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ (النحل:90)
ترجمہ: اور ہم نے تیری طرف ایسی کامل کتاب نازل کی ہے جس میں ہر چیز کی وضاحت ہے
حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی معہود علیہ السلام اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں:
ہر چند میرا مذہب یہی ہے کہ قرآن اپنی تعلیم میں کامل ہے اور کوئی صداقت اس سے
باہر نہیں کیونکہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے.وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ یعنی ہم
نے تیرے پر وہ کتاب اتاری ہے جس میں ہر ایک چیز کا بیان ہے اور پھر فرماتا ہے مَا فَرَّطْنَا
فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ [الانعام : 39] یعنی ہم نے اس کتاب سے کوئی چیز با ہر نہیں رکھی.الحق مباحثہ لدھیانہ روحانی خزائن جلد جلد 4 صفحہ 80,81)
ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں:
اور پھر وہ معارف عالیہ ناقص اور نا تمام طور پر نہیں لکھے گئے بلکہ کما و کیفا کامل درجہ پر واقعہ
ہیں اور کسی عاقل کی عقل کوئی ایسی دینی صداقت پیش نہیں کر سکتی جو ان سے باہر رہ گئی ہو اور کسی
باطل پرست کا کوئی ایسا وسوسہ نہیں جس کا ازالہ اس کلام میں موجود نہ ہو.ان تمام حقائق ورقائق
کے التزام سے کہ جو دوسری طرف ضرورات حقہ کے التزام کے ساتھ وابستہ ہیں فصاحت
بلاغت کے ان اعلی کمالات کو ادا کرنا جن پر زیادت متصور نہ ہو.یہ تو نہایت بڑا کام ہے کہ جو
بشری طاقتوں سے بہ بداہت نظر بلند تر ہے.براہین احمدیہ جلد چہارم حاشیہ نمبر گیارہ روحانی خزائن جلد اول صفحہ 399 ایڈیشن اول صفحہ 335)
مگر یہ بیان اس وقت کھلتا ہے جب اس کی ضرورت ظاہر ہوتی ہے.اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے :
وَ إِنْ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَ مَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ - (الحجر:22)
ترجمہ: اور ہمارے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں اور ہم اسے ایک معلوم اندازے کے مطابق
Page 260
الذكر المحفوظ
244
ہی نازل کرتے ہیں.پس ہر ایک زمانہ کی ضرورت کے تمام مضامین قرآن کریم کی آیات میں اپنی اپنی ترتیب کے مطابق ایک
دوسرے کے متوازی چل رہے ہوتے ہیں.مضامین کے غیر محدود ہونے کی وجہ سے ان کی ترتیب کا تنوع بھی غیر
محدود ہے.یہ قرآنی مضامین حسب حالات اور حسب موقع گہری نظر سے مطالعہ کرنے پر ہی منکشف ہوتے ہیں اور
سرسری مطالعہ کرنے والے کو نصیب نہیں ہو سکتے.اسی طرح بار بار مطالعہ کرنے سے وہ مضامین بھی منکشف ہوتے
ہیں جو ایک بار مطالعہ کرنے سے نظروں سے اوجھل رہ جاتے ہیں.پھر ایک خاص نکتہ نظر سے مطالعہ کیا جائے یا
کسی خاص مضمون پر توجہ مرکوز ہو تو دوسرے مضامین نظر سے اوجھل رہ جاتے ہیں.چونکہ اس کتاب کا منبع ایک
غیر محدودسر چشمہ علم ہے اس لیے جتنا بھی مطالعہ کیا جائے ، محدود قومی اور محدود علم کے انسان کے لیے ہر بار اس
میں نئے سے نئے علوم کی طرف راہنمائی ہوگی اور ہر شخص اس سے بقدر استطاعت فائدہ تو اُٹھا سکتا ہے مگر آگے
بڑھ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں ضروری مضمون قرآن کریم میں بیان نہیں ہے.قرآن کریم مضمون کو اس کی طبیعی ترتیب سے بیان فرماتا ہے
قرآن کریم اپنے بیان میں اول سے آخر تک مضمون کو اس کی طبعی ترتیب سے بیان کرتا ہے.چنانچہ پہلی ہی
سورت ،سورۃ الفاتحہ سے ہی یہ ترتیب ملتی ہے.حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں.رَبِّ الْعَلَمِيْنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِلِكِ يَوْمِ الدِّينِ.اس جگہ سورۃ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ
نے اپنی چار صفتیں بیان
فرمائیں.یعنی رب العالمین.رحمان.رحیم.مالک یوم الدین اور ان
ہر چہار صفتوں میں سے رب العالمین کو سب سے مقدم رکھا اور پھر بعد اس کے صفت رحمان کو
ذکر کیا.پھر صفت رحیم کو بیان فرمایا.پھر سب کے اخیر صفت مالک یوم الدین کو لائے.پس
سمجھنا چاہیے کہ یہ ترتیب خدائے تعالیٰ نے کیوں اختیار کی ؟ اس میں نکتہ یہ ہے کہ ان صفات
اربعہ کی ترتیب طبعی یہی ہے اور اپنی واقعی صورت میں اسی ترتیب سے یہ مفتیں ظہور پذیر ہوتی ہیں.براہین احمد یہ روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 444 حاشیہ نمبر 11) حمدیہ 1
المصل
حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب خلیفہ مسیح الثانی مصلح موعود رضی اللہ عنہاس بارہ میں فرماتے ہیں:
در حقیقت قرآنی مضامین کی ترتیب عام کتب کی ترتیب کے مطابق نہیں بلکہ طبعی ترتیب ہے
وہ اپنے مضامین میں جو تر تیب رکھتا ہے وہ اس ترتیب سے علیحدہ ہے جو انسان اپنی کتابوں میں
رکھتے ہیں.قرآن کریم اس چیز کو جو سب سے پہلے بیان ہونی ضروری ہو بیان کرتا ہے اور پھر اس
Page 261
قرآن کریم میں تحریف کے الزامات کے جواب
245
کے متعلق انسانی قلب میں پیدا ہو نیوالے تمام وساوس اور شبہات کا ازالہ کرتا ہے.مثلاً جنگ ہے
اس کے متعلق جو سوال پیدا ہونگے ان کو بیان کر لگا پھر ان سے جو سوال پیدا ہوگا وہ بیان کرتا چلا
جائیگا اور چونکہ ایسے سوالات طبعی ہوتے ہیں اس لیے ان کے جوابات کا قلوب پر خاص اثر پڑتا
ہے اسی طبعی ترتیب سے اس جگہ بھی کام لیا گیا ہے.چنانچہ جنگ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے
شراب اور جوئے کا ذکر کر دیا جو جنگ سے براہ راست تعلق رکھنے والی چیزیں تھیں اور جب جوئے
سے اخراجات جنگ پورے کرنے کے طریق سے روک دیا تو طبعی طور پر یہ سوال پیدا ہوا کہ پھر یہ
اخراجات کس طرح پورے ہونگے اس کے لیے بتایا کہ ضرویات زندگی پوری کرنے کے بعد جور قم
بچ رہے وہ خرچ کرنی چاہیے پھر ایک ہی لفظ عفو استعمال کر کے اس میں مختلف مدارج کا ذکر کر کے
بتایا کہ ادنیٰ درجہ کون سا ہے اور اعلیٰ درجہ کونسا.اس کے بعد یتامیٰ کے حقوق کو لے لیا.کیونکہ جنگ
کے بعد لازماً اس سوال نے اہمیت اختیار کر لینی تھی.غرض قرآن کریم کا یہ کمال ہے کہ اس نے
اپنے مضامین میں ایک ایسی اعلیٰ درجہ کی ترتیب رکھی ہے جو فطرت انسانی کے عین مطابق ہے ادھر
ایک سوال فطرت انسانی میں پیدا ہوتا ہے اور ادھر قرآن کریم میں اس کا جواب موجود ہوتا ہے.( تفسیر کبیر جلد دوز بر آیت البقرة : 222 صفحہ 499)
نظام ترتیب قرآن، قوانین قدرت کے مطابق ہے
اسی طرح قرآن کریم کے مضامین کی ایک ترتیب قوانین قدرت کے مطابق ہے.حضرت مسیح موعود علیہ السلام
قرآن کریم کی اس قسم کی ترتیب کے بارہ میں ان الفاظ میں راہنمائی عطا فرماتے ہیں:
قرآن کریم اخلاقی تعلیم میں قانونِ قدرت کے قدم بہ قدم چلا ہے.رحم کی جگہ جہاں
تک قانون قدرت اجازت دیتا ہے رحم ہے اور قہر اور سزا کی جگہ اسی اصول کے لحاظ سے قہر اور
سزا اور اپنی اندرونی اور بیرونی تعلیم میں ہر ایک پہلو سے کامل ہے اور اس کی تعلیمات نہایت
درجہ کے اعتدال پر واقعہ ہیں جو انسانیت کے سارے درخت کی آب پاشی کرتی ہیں نہ کسی ایک
شاخ کی.اور تمام قومی کی مربی ہیں نہ کسی ایک قوت کی اور درحقیقت اسی اعتدال اور موزونیت
کی طرف اشارہ ہے جو فرمایا ہے.كِتَابًا مُّتَشَابِهًا (الزمر: 24 ) پھر بعد اس کے مَثَانِيَ کے
لفظ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ قرآن کریم کی آیات معقولی اور روحانی دونوں طور کی
روشنی اپنے اندر رکھتی ہیں.کرامات الصادقین.روحانی خزائن.جلد 7 صفحہ 59-58)
Page 262
الذكر المحفوظ
246
حضرت مرزا بشیر احمد صاحب اس نظام ترتیب کے بارہ میں بیان کرتے ہیں:
قرآن شریف جو خدا کا قول ہے اس میں اسی قسم کا اصول ترتیب مد نظر رکھا گیا ہے جو خدا
کے فعل یعنی صحیفہ قدرت میں پایا جاتا ہے.یعنی جس طرح اس جسمانی عالم میں دنیا کی مادی
زندگی اور ترقی و بہبودی کے سامان مہیا کیے جا کر اس میں ترتیب رکھی گئی ہے اسی طرح کی خدا
کے قول یعنی قرآن شریف میں ایک ترتیب ہے جو علم النفس کے ان ابدی اصول کے ماتحت قائم
کی گئی ہے جو دنیا کی اخلاقی اور تمدنی اور روحانی زندگی اور اصلاح و ترقی کے لیے بہترین اثر
رکھتے ہیں اور لطف یہ ہے کہ جس طرح بعض لوگوں کو اس عالم جسمانی میں کوئی ترتیب نظر نہیں
آتی اس طرح روحانی بینائی سے محروم لوگوں کو قرآنی ترتیب بھی نظر نہیں آتی.مگر جو لوگ گہرے
مطالعہ کے عادی ہیں اور روحانی کلام کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے اپنے اندر ضروری بینائی اور
تقدس وطہارت رکھتے ہیں وہ اس ترتیب کو علی قدر مراتب سمجھتے اور اس کے اثر کو اپنے نفوس میں
محسوس کرتے ہیں.( سيرة خاتم النبین حصہ دوم زیر عنوان ترتیب قرآن صفحه 535)
ترتیب قرآن عالم جسمانی اور عالم روحانی کے مطابق ہے
قرآن کریم کی ترتیب عالم جسمانی کی ترتیب کے مشابہ بھی ہے.جس طرح اس عالم رنگ و بُو میں ایک
عجیب حسن اور توازن پایا جاتا ہے جو دیدہ بینا کی طراوت کا سامان مہیا کرتا ہے اسی طرح قرآن کریم میں بھی
غیر معمولی حسن ہے جو اس جہان پر غور کرنے والوں پر ہر زمانہ میں گھلتا رہا ہے.اس کی ایک اور دلیل یہ ہے کہ
عالم جسمانی اسی خالق کا فعل ہے قرآن کریم جس کا قول ہے.پس قول اور فعل میں مطابقت ہونی چاہیے اور
ہے.حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں:
رَبِّ الْعَلَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ.اس جگہ سورۃ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ
نے اپنی چار صفتیں بیان فرمائیں.یعنی رب العالمین.رحمان.رحیم.مالک یوم الدین اور ان
ہر چہار صفتوں میں سے رب العالمین کو سب سے مقدم رکھا اور پھر بعد اس کے صفت رحمان کو
ذکر کیا.پھر صفت رحیم کو بیان فرمایا.پھر سب کے اخیر صفت مالک یوم الدین کو لائے.پس
سمجھنا چاہیے کہ یہ ترتیب خدائے تعالیٰ نے کیوں اختیار کی ؟ اس میں نکتہ یہ ہے کہ ان صفات
اربعہ کی ترتیب طبیعی یہی ہے اور اپنی واقعی صورت میں اسی ترتیب سے یہ صفتیں ظہور پذیر ہوتی
ہیں.اور کمال بلاغت اسی کا نام ہے کہ جو صحیفہ فطرت میں ترتیب ہو.وہی ترتیب صحیفہ الہام
Page 263
قرآن کریم میں تحریف کے الزامات کے جواب
247
میں بھی ملحوظ رہے.کلام بلیغ کے لئے یہ نہایت ضروری ہے کہ نظام کلام کا نظام طبعی کے ایسا
مطابق ہو کہ گویا اسی کی عکسی تصویر ہو اور جو امر طبعاً اور وقوعاً مقدم ہو اس کو وضعا بھی مقدم رکھا
جائے.سو آیت موصوفہ میں یہ اعلیٰ درجہ کی بلاغت ہے کہ باوجود کمال فصاحت اور خوش بیانی
کے واقعی ترتیب کا نقشہ کھینچ کر دکھلا دیا ہے اور وہی طرز بیان اختیار کی ہے جو کہ ہر یک صاحب
نظر کو نظام عالم میں بدیہی طور پر نظر آرہی ہے.کیا یہ نہایت سیدھا راستہ نہیں ہے کہ جس ترتیب
سے نعماء الہی صحیفہ فطرت میں واقعہ ہیں.اسی ترتیب سے صحیفہ الہام میں بھی واقعہ ہوں.سوایسی
عمدہ اور پر حکمت ترتیب پر اعتراض کرنا حقیقت میں انہیں اندھوں کا کام ہے جن کی بصیرت اور
بصارت دونوں یکبارگی جاتی رہی ہیں.(براہین احمد یہ روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 444 حاشیہ نمبر 11)
ایک کو تاہ بین معترض کہہ سکتا ہے کہ یہ کیا کہ زمین پر کہیں پہاڑ ہیں کہیں میدان ، کہیں سبزہ زار ہیں اور کہیں ریگزار ؟
مگر علوم ارضیات کے ماہر تحقیقات کے بعد اس زمین پر جاری نظام کی کامل ترتیب اور توازن کے قائل ہیں.یہی
حال باقی کا ئنات کا ہے.ایک ناواقف کے نزدیک ستاروں وغیرہ میں کوئی ترتیب نہیں ہے.مگر astronomy
والے ان ستاروں کے نظام کے توازن کے بارے میں ایسے ایسے حقائق آشکار کر چکے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی
ہے کہ ایسا کامل اور مکمل اور با رابط نظام ہے.حضرت
مسیح موعود علیہ السلام قرآن کریم کے بیان فرمود تخلیق عالم جسمانی
کے مراحل کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ عالم جسمانی اور عالم روحانی خدا تعالیٰ کی تخلیق ہے اور ان
میں کامل تطابق ہے اسی طرح قرآن کریم کا اسلوب بیان بھی عالم جسمانی اور عالم روحانی کے مراتب ستہ کے عین
مطابق ہے.کیونکہ قرآن کریم خدا کا قول ہے اور عالم جسمانی اور عالم روحانی خدا کا فعل ہیں اور خدا کے قول وفعل
میں تطابق ہے.چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام تخلیق کائنات کے چھے مراحل اور انسان کی جسمانی تخلیق کے چھے
مراحل کو وضاحت سے بیان فرما کر ان کی انسان کی روحانی تخلیق کے چھے مراحل سے مطابقت کی وضاحت
فرماتے ہیں.( آئینہ کمالات اسلام روحانی خزائن جلد 5 صفحه 172 تا 211 حاشیه در حاشیہ ) اور پھر یہ ثابت فرماتے ہیں کہ
کلام الہی بھی اس نظام ترتیب پر مشتمل ہے.گویا ایک جسمانی عالم ہے اور ایک روحانی عالم ہے اور ایک عالم کلامِ الہی
ہے اور ان کا نظام ترتیب ایک دوسرے کے مشابہ ہے.چنانچہ ایک جگہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں:
دیکھو خدا تعالیٰ کے نظام شمسی میں کیسی ترتیب پائی جاتی ہے اور خود انسان کی جسمانی ہیکل
کیسی ابلغ اور احسن ترتیب پر مشتمل ہے پھر کس قدر بے ادبی ہوگی اگر اس احسن الخالقین کے
کلمات پر حکمت کو پراگندہ اور غیر منتظم اور بے ترتیب خیال کیا جائے.تریاق القلوب - روحانی خزائن.جلد 15 صفحہ 457-456 حاشیہ )
Page 264
الذكر المحفوظ
248
قرآن کریم کی ترتیب بیان باعتبار ظاہر
ترتیب کے ضمن میں ایک یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ قرآن کریم واقعات اور مضامین کو ان کی ظاہری ترتیب سے
بیان نہیں کرتا.ابن وراق بھی خوب نمک مرچ لگا کر یہ اعتراض بیان کرتا ہے.مضامین کی ترتیب کے بارہ میں ہم دیکھ
چکے ہیں کہ ایک غیر معمولی حسنِ ترتیب ہے.ظاہری ترتیب کی ایک اور مثال درج کی جاتی ہے: حضرت مسیح موعود
علیہ السلام تقویٰ کے قرآن کریم کی علت غائی ہونے کی وضاحت فرماتے ہوئے قرآن
کریم کی ترتیب بیان فرماتے ہیں:
پھر دیکھو کہ تقویٰ ایسی اعلیٰ درجہ کی ضروری شے قرار دیا گیا ہے کہ قرآن کریم کی علت غائی
اسی کو ٹھہرایا ہے چنانچہ دوسری سورۃ کو جب شروع کیا ہے تو یوں ہی فرمایا ہے: الم ذلِكَ
الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ (البقره:3-2 ) میرا مذ ہب یہی ہے کہ قرآن کریم کی
یہ ترتیب بڑا مرتبہ رکھتی ہے.خدا تعالیٰ نے اس میں علل اربعہ کا ذکر فرمایا ہے.علت فاعلی،
مادی ،صوری، غائی.ہر ایک چیز کے ساتھ یہ چارہی علل ہوتی ہیں.قرآن کریم نہایت اکمل طور
پر ان کو دکھاتا ہے.آلم اس میں یہ اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بہت جاننے والا ہے.اس کلام
کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے.یعنی خدا اس کا فاعل ہے.ذلِكَ
الكتب یہ مادہ بتایا.یا یہ کہو کہ یہ علت مادی ہے.علت صوری لَا رَيْبَ فِيهِ ہر ایک چیز میں شک
وشبہ اور ظنون فاسدہ پیدا ہو سکتے ہیں.مگر قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ اس میں کوئی ریب
نہیں ہے.لا ریب اسی کے لیے ہے.اب جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی شان یہ بتائی ہے
کہ لَا رَيْبَ فِيهِ.تو ہر ایک سلیم الفطرت اور سعادت مند انسان کی روح اچھلے گی اور خواہش
کرے گی کہ اس کی ہدایتوں پر عمل کرے.لملفوظات جلد اول صفحہ 282)
اب دنیا کی کوئی مذہبی کتاب اُٹھا کر دیکھ لیں.اس خوبصورتی اور جامعیت سے اپنا مقصد بیان نہیں کرتی.واقعات کے بیان میں تاریخ کے اعتبار سے ترتیب نہ ہونے کے بارہ میں بھی اعتراض کیے جاتے ہیں.اب
یہ اعتراض وہی شخص کرے گا جو دعوئی خواہ کچھ بھی کرتا ہو مگر قرآن کریم کے بارہ میں یہ سمجھ ہی نہیں سکا کہ یہ کوئی
تاریخ کی کتاب نہیں ہے.مگر پھر بھی قرآن کریم کا غیر معمولی اعجاز ہے کہ ترتیب مضمون
کو بھی نہیں چھوڑتا اور
واقعات کو بھی اُن کی ظاہری ترتیب کے لحاظ سے مضمون میں پروتا چلا جاتا ہے.حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس
سلسلہ میں راہنمائی کرتے ہوئے فرماتے ہیں:
یادر ہے کہ عام محاورہ قرآن کریم کا ہے اور صدہا نظیریں اس کی اس پاک کلام میں موجود ہیں
کہ ایک دنیا کے قصہ کے ساتھ آخرت کا قصہ پیوند کیا جاتا ہے اور ہر ایک حصہ کلام کا اپنے قرائن سے
Page 265
قرآن کریم میں تحریف کے الزامات کے جواب
249
دوسرے حصہ سے تمیز رکھتا ہے اس طرز سے سارا قرآن شریف بھرا پڑا ہے.مثلاً قرآن
کریم میں شق القمر
کے معجزہ کو ہی دیکھو کہ وہ ایک نشان تھا لیکن ساتھ اس کے قیامت کا قصہ چھیڑ دیا گیا.جس کی وجہ سے
بعض نادان قرینوں
کو نظر انداز کر کے کہتے ہیں کہ شق القمر وقوع میں نہیں آیا بلکہ قیامت کو ہوگا.شہادت القرآن.روحانی خزائن.جلد 6 صفحہ 311 حاشیہ )
مگر اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ قرآن کریم واقعات کی تاریخی ترتیب کو مد نظر رکھتا ہی نہیں.حضرت مرزا غلام
احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی معہود علیہ السلام فرماتے ہیں:
اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ اس بات پر دلیل کیا ہے کہ قرآن شریف میں اول سے آخر تک
ظاہری ترتیب کا لحاظ رکھا گیا ہے.بجز دو چار مقام کے جو بطور شاذ و نادر ہیں.تو یہ ایک سوال
ہے کہ خود قرآن شریف پر ایک نظر ڈال کر حل ہو سکتا ہے.یعنی اس پر یہ دلیل کافی ہے کہ اگر تمام
قرآن اول سے آخر تک پڑھ جاؤ تو بجز چند مقامات کے جو بطور شاذ و نادر کے ہیں.باقی تمام
قرآنی مقامات کو ظاہری ترتیب کی ایک زرین زنجیر میں منسلک پاؤ گے اور جس طرح اس حکیم
کے افعال میں ترتیب مشہور ہو رہی ہے یہی ترتیب اس کے اقوال میں دیکھو گے اور یہ اس بات
پر کہ قرآن ظاہری ترتیب کو محوظ رکھتا ہے ایسی پختہ اور بدیہی اور نہایت قوی دلیل ہے کہ اس
دلیل کو سمجھ کر اور دیکھ کر بھی پھر مخالفت سے زبان کو بند نہ رکھنا صریح بے ایمانی اور بددیانتی ہے.اگر ہم اس دلیل کو مبسوط طور پر اس جگہ لکھیں تو گویا تمام قرآن شریف کو اس جگہ درج کرنا ہوگا
اور اس مختصر رسالہ میں یہ گنجائش نہیں.( تریاق القلوب : روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 456 حاشیہ)
اور جہاں قرآن کریم میں دو چار مقامات پر واقعات کی ظاہری ترتیب کو مد نظر نہیں رکھا گیا تو وہاں بھی بلاوجہ
نہیں بلکہ ایک اعلیٰ مقصد اور گہری حکمت کے پیش نظر ایسا کیا گیا ہے.حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں:
یہ تو ہم قبول کرتے ہیں شاذ و نادر کے طور پر قرآن شریف میں ایک دو مقام ایسے بھی ہیں کہ جن
میں مثلاً عیسی پہلے آیا اور موسیٰ بعد میں آیا.یا کوئی اور نبی متاخر جو پیچھے آنے والا تھا اس کا نام پہلے بیان
کیا گیا اور جو پہلا تھا وہ پیچھے بیان کیا گیا.لیکن یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ یہ چند مقامات بھی خالی از
ترتیب ہیں.بلکہ ان میں بھی ایک معنوی ترتیب ہے جو بیان کرنے کے سلسلہ میں بعض مصالح کی وجہ
سے پیش آگئی ہے.لیکن اس میں کچھ بھی شک نہیں کہ قرآن کریم ظاہری ترتیب کا اشد التزام رکھتا ہے
اور ایک بڑا حصہ قرآنی فصاحت اسی سے متعلق ہے.( تریاق القلوب : روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 456 حاشیہ )
چنانچہ یہ معنوی ترتیب اور اس کی حکمت بیان کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں:
یجی اور عیسی علیہ السلام کے قصہ کو ایک جا جمع کرنا اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ جیسے بیٹی علیہ
Page 266
الذكر المحفوظ
250
السلام کی پیدایش خوارق طریق سے ہے ویسے ہی مسیح کی بھی ہے پھر یحیی علیہ السلام کی پیدائیش کا حال
بیان کر کے مسیح کی پیدائیش کا حال بیان کیا ہے.یہ ترتیب قرآنی بھی بتلاتی ہے کہ ادنیٰ حالت سے اعلیٰ
حالت کی طرف ترقی کی ہے.یعنی جس قدر معجز نمائی کی قوت بیٹی کی پیدایش میں ہے اس سے بڑھ کر
مسیح کی پیدائیش میں ہے.اگر اس میں کوئی معجزانہ بات نہ تھی تو بیٹی کی پیدائیش کا ذکر کر کے کیوں
ساتھ ہی مریم کا ذکر چھیڑ دیا اس سے کیا فائدہ تھا یہ اسی لیے کیا کہ تاویل کی گنجایش نہ رہے ان دونوں
بیانوں کا ایک جاذکر ہونا اعجازی امر کو ثابت کرتے ہیں.( ملفوظات جلد سوم صفحہ 281-280)
قرآن کریم کی سورتوں میں مضامین کا ایک نظام ترتیب مقطعات کے حوالہ سے بھی ہے.قرآن کریم کی ترتیب
کے اس پہلو کو بیان کرتے ہوئے حضرت خلیفتہ اسیح الثانی اس طرف توجہ دلاتے ہیں کہ ایک جیسے مقطعات والی سورتیں
ایک ترتیب سے ہیں نیز یہ کہ ایک جیسے مقطعات والی سورتوں کے مضامین بھی ایک جیسے ہی ہیں.جب حروف
مقطعات تبدیل ہوتے ہیں تو مضمون بھی بدل جاتا ہے.حضرت میر محمد اسماعیل صاحب نے سورۃ الفاتحہ کا باقی تمام
سورتوں سے یہ تعلق بیان
فرمایا ہے کہ سورۃ الفاتحہ بھی انہی حروف پر مشتمل ہے جو کہ مقطعات کی صورت میں قرآن کریم
میں آئے ہیں.اس لحاظ سے سورۃ الفاتحہ کا مقطعات کے تحت آنے والی سورتوں کے مضامین سے گہرا تعلق ہے.اب تک درج کی گئی مثالوں سے اندازہ ہو چکا ہوگا کہ قرآن کریم کی ترتیب میں بہت تنوع ہے اور بہت سے
مختلف مضامین کے لحاظ سے آیات اور سورتیں ایک دوسرے سے تعلق رکھتی ہیں اور بہت سی ترتیبہیں اپنے اپنے
انداز میں عام فہم اور آسانی سے سمجھ میں آنیوالی ہیں اور ایک حیرت انگیز رنگ اپنے اندر رکھتی ہیں.قرآن کریم کیونکہ ساری دُنیا کے انسانوں کے لیے یکساں طور پر ہدایت دینے کے لیے نازل کیا گیا ہے اس
لیے بحث کا ایسا طریقہ اختیار کرنا لازمی تھا کہ ہر قاری اپنے اپنے مزاج اور طبعیت کے مطابق فائدہ اٹھائے اور ایسا
نہ ہو کہ ایک انسان تو فائدہ اٹھا رہا ہو، اور دوسرا پڑھتے ہوئے عدم دلچپسی کا شکار ہو.چنانچہ قرآن کریم کا یہ بھی ایک
خاص انداز ہے کہ کسی صداقت کے بیان کرتے وقت عام لکھنے والوں کی طرح بحث نہیں کرتا بلکہ متعلقہ مضامین کو
بیان کرتا چلا جاتا ہے.گویا ایک گلدستہ ہے مضامین کا.گلدستے میں ہر پھول جسکا اپنا ایک انفرادی اور جدا گانہ حسن
اور خوبصورتی بھی ہوتی ہے، باقی پھولوں کے ساتھ مل کر الگ ہی نظارہ پیش کرتا ہے.یہی حال قرآنی آیات کا
ہے.مختلف آیات مل کر ایک مضمون کی وضاحت کرتی ہیں، اور ان کا جدا گانہ حسن بھی محسوس کیا جاسکتا ہے.جب
قاری ان سب آیات کے مطالعہ کے بعد آخر پر پہنچتا ہے تو اس کے ذہن میں ایک گلدستہ کی طرح اس صداقت کی
ایک واضح تصویر بن چکی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ بہت سے ایسے مضامین بھی علم میں آتے ہیں کہ اگر کوئی دوسری
ہستی اس مضمون کو بیان کر رہی ہوتی تو ہرگز یہ زائد مضامین علم میں نہ آتے نیز ہر آیت اپنی جگہ الگ مضمون بھی بیان
Page 267
قرآن کریم میں تحریف کے الزامات کے جواب
251
کر رہی ہوتی ہے.ایسے ذہن جو کہ مناظرانہ طرز پر کلام سمجھنے کے عادی ہوتے ہیں ان کے لیے دلائل کا ایک انبار
موجود ہوتا ہے اور جو ذہن اس طریق سے ہٹ کر ہلکے پھلکے انداز میں کہانی کی طرح حقائق جانے کے شوقین ہوتے
ہیں وہ بھی اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں.عالم شخص اپنے انداز میں اسے پڑھتا ہے اور ایک بچہ بھی اس سے محفوظ
ہو رہا ہوتا ہے.پھر اگر قاری اس کو آخر تک نہ بھی پڑھے تو بھی ذہن میں کوئی تشنگی نہیں رہتی کہ اب تک جو پڑھا وہ
نامکمل بحث تھی.بلکہ جس آیت پر بھی ختم کرتا ہے وہاں تک ایک مکمل مضمون اس کے ذہن میں بیٹھ چکا ہوتا ہے.حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں:
قرآن شریف نے تائید دین میں اور علوم سے بھی اعجازی طور پر خدمت لی ہے اور منطق اور
طبعی اور فلسفہ اور ہیئت اور علم نفس اور طبابت اور علم ہندسہ اور علم بلاغت و فصاحت وغیرہ علوم کے
وسائل سے علم دین کا سمجھانا اور ذہن نشین کرنا یا اس
کا تفہیم درجہ بدرجہ آسان
کر دینا یا اس پر کوئی برہان
قائم کرنا یا اس سے کسی نادان کا اعتراض اٹھا نا مد نظر رکھا ہے غرض طفیلی طور پر یہ سب علوم خدمت
دین کے لیے بطور خارق عادت قرآن شریف میں اس عجیب طرز سے بھرے ہوئے ہیں جن سے
ہر یک درجہ کا ذہن فائدہ اٹھا سکتا ہے.(سرمہ چشم آریہ.روحانی خزائن.جلد 2 صفحہ 75 حاشیہ )
قرآن کریم کی ترتیب کے تنوع پر غور کرتے ہوئے مختلف مفسرین نے مختلف ترتیبیں بیان کی ہیں اور وہ سب ہی
اپنی اپنی جگہ خوب ہیں.حضرت مسیح موعود علیہ السلام قرآن کریم کی تفسیر کرتے ہوئے آیات اور سور کی لطیف ترتیب
بیان کرتے جاتے ہیں.گزشتہ سطور میں آپ کے بیان فرمودہ قرآن کریم کے دستور بیان سے چند نکات معرفت
درج کیے گئے ہیں.خلیفہ اسی الثانی نے اپنی مشہور زمانہ تفسیر کبیر میں جابجا قرآن کریم کی آیات کی ترتیب اور
سورتوں کے مابین رابط کی وضاحت کی ہے.حضرت خلیفتہ امسیح الرابع رحمہ اللہ نے اپنے ترجمۃ القرآن میں سورتوں
کے تعارفی نوٹوں میں سورتوں کی باہمی ترتیب کی وضاحت کی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے قرآن کریم کی آیات اور سور
میں ربط اور تسلسل ہے اور اس میں بہت تنوع ہے.مختلف انداز سے قرآن کریم کی آیات اور سورتیں ایک دوسرے
سے متعلق ہیں اور ان کے مختلف مضامین کے آپس میں ایک سے زیادہ تعلق ہیں.مختلف مضامین کے لحاظ سے اگر ان
دونوں جلیل القدر حضرات کی بیان فرمودہ ترتیب قرآن ہی مکمل طور پر بیان کی جائے تو ایک ضخیم کتاب تیار ہو جائے
گی.قرآن کریم کے حسنِ ترتیب پر بے شمار معارف اور نکات جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے خلفاء کی عطا
ہیں ، سب کا درج کرنا ممکن بھی نہیں.آخر پر یہ ذکر کر کے اس نا پیدا کنار مضمون
کو ختم کرتا ہوں کہ قرآن
کریم بسم اللہ کی
”ب“ سے لے کر الناس کی ”س“ تک مرتب اور باربہ کلام ہے.حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں:
پس سورۃ فاتحہ میں ان تینوں دعاؤں کی تعلیم بطور براءت الاستہلال ہے یعنی وہ اہم مقصد جو
وو
66
Page 268
الذكر المحفوظ
252
قرآن میں مفصل بیان کیا گیا ہے سورۃ فاتحہ میں بطور اجمال اس کا افتتاح کیا ہے اور پھر سورۃ تنبت
اور سورۃ اخلاص اور دوسورۃ فلق اور سورۃ الناس میں ختم قرآن کے وقت میں انہی دونوں بلاؤں سے
خدا تعالی کی پناہ مانگی گئی ہے.پس افتتاح کتاب اللہ بھی انہی دونوں دعاؤں سے ہوا اور پھر اختتام
کتاب اللہ بھی انہی دونوں دعاؤں پر کیا گیا.(تحفہ گولڑر و بی.روحانی خزائن.جلد 17 صفحہ 219-217)
قرآن کریم میں اعادہ و تکرار اور اس کا حقیقی فلسفہ
ابن وراق اپنی نابینائی کا رونا ان الفاظ میں بھی روتا ہے:
repetition of the same thyme word or rhyme phrase
in adjoining verses
(Ibn Warraq: Why I am Not A Muslim, Prometheus Books, New
York, 1995, under heading; The Koran: Pg :112)
ایک طرف تو قرآن کریم اپنے اسلوب بیان کے غیر معمولی اور بے مثل ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور دوسری
طرف اس دعویٰ کی تائید میں ہر دور میں اہل علم ، بلا تمیز مذہب و عقیدہ قرآن کریم کے اس اسلوب بیان کے انتہائی
درجہ کمل اور اثر انگیز ہونے کی گواہی دیتے چلے آئے ہیں.پس کوئی عربی سے نابلد، تعصب کی آگ میں جلنے والا
اور جہالت کے اندھیروں میں بھٹکنے والا، یا کوئی مخمور شراب نوش اگر اس معجزانہ ترتیب اور خوبصورت اسلوب کو
نہیں سمجھ سکا تو اس سے قرآن کریم پر کیا اثر پڑا ؟
گزشتہ سطور میں یہ ذکر گزر چکا ہے کہ تعلیم اور تدریس ہونے کے اعتبار سے قرآن کریم کے بیان میں ایک قسم کا
اعادہ ہے.اس انداز کے اختیار کرنے میں ایک حکمت یہ ہے کہ قرآن کریم میں ہر موضوع کو انسانی فطرت کے تنوع
کے پیش نظر مختلف انداز میں بار بار بیان کیا گیا ہے تا کہ ہر فطرت کا انسان اپنی قابلیت اور ذوق کے مطابق اس سے
مستفیذ ہو سکے.ہر موقع کے مطابق انبیاء کے وقت کے حالات کو مثال کے طور پر پیش کیا گیا ہے تا کہ قرآن کریم کا
اصل اور بنیادی موضوع یعنی خدائے واحد کی عبادت اور اس کی اصل غرض، ہر طور سے واضح اور راسخ ہو جائے.حضرت مسیح موعود علیہ السلام کتاب اللہ کے مضامین میں تصریف اور اعادہ و تکرار کے حقیقی فلسفہ پر روشنی
ڈالتے ہوئے عقل اور فطرت انسانی کی رو سے دلائل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:
یہ تو احمقوں کی خشک منطق ہے جو کہتے ہیں کہ بار بار تکرار سے بلاغت جاتی رہتی ہے.وہ کہتے
رہیں.قرآن شریف کی غرض تو بیمار کو اچھا کرنا ہے وہ تو ضرور ایک مریض کو بار بار دوادے گا.اگر یہ
قاعدہ صحیح نہیں تو پھر ایسے معترض جب کوئی ان کے ہاں بیمار ہو جاوے تو بار بار دوا کیوں دیتے ہیں
اور آپ کیوں بار بار دن رات تکرار میں اپنی غذا، لباس وغیرہ امور کا تکرار کرتے ہیں؟
Page 269
قرآن کریم میں تحریف کے الزامات کے جواب
253
پچھلے دنوں میں نے کسی اخبار میں پڑھا تھا کہ ایک انگریز نے محض اس وجہ سے خود کشی کر لی
کہ بار با روہی دن رات غذا مقرر ہے اور میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا.(ملفوظات جلد چہارم صفحہ 457)
اعادہ کی ایک حکمت کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:
قرآنی ترتیب کا یہ اصول ہے کہ وہ اپنے پہلے مضمون کو آخر میں پھر دُہرا دیتا ہے اور یہ اس بات کی
علامت ہوتی ہے کہ یہاں گزشتہ بحث ختم ہوتی ہے.اور آئندہ نیا مضمون شروع ہوتا ہے.( تفسیر کبیر جلد دوم تفسیر آیت البقرة:لن تمسنا النار الا اياما معدودات)
ابن وراق قرآن کریم میں اعادہ و تکرار پر اعتراض کرتے ہوئے سورۃ الرحمان میں دہرائی جانے والی آیت
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ( آیت:14) کو خصوصیت سے پیش کرتا ہے.حضرت اقدس
مسیح موعود علیہ السلام
سورۃ رحمن میں اس تکرار کی حکمت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:
اس قسم کا التزام اللہ تعالیٰ کے کلام کا ایک ممتاز نشان ہے.انسان کی فطرت میں یہ امر واقع ہوا
ہے کہ موزوں کلام اسے جلد یاد ہو جاتا ہے اس لیے فرمایا وَ لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ
للذكر القمر : 23) یعنی بیشک ہم نے یاد کرنے کے لیے قرآن شریف کو آسان کر دیا ہے....فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِ بنِ بار بار توجہ دلانے کے واسطے ہے.اسی تکرار پر نہ جاؤ قرآن
شریف میں اور بھی تکرار ہے.میں خود بھی تکرار کو اسی وجہ سے پسند کرتا ہوں.میری تحریروں کو اگر کوئی
دیکھتا ہے تو وہ اس تکرار کو بکثرت پائے گا.حقیقت سے بے خبر انسان اس کو منافی بلاغت سمجھ لے گا اور
کہے گا کہ یہ بھول کر لکھا ہے حالانکہ یہ بات نہیں ہے.میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید پڑھنے والا پہلے جو کچھ
لکھا ہے اسے بھول گیا ہو اس لیے بار بار یاد دلاتا ہوں تا کہ کسی مقام پر تو اس کی آنکھ کھلے.إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالْنِيَّاتِ.علاوہ بریں تکرار پر اعتراض ہی بے فائدہ ہے اس لیے کہ یہ بھی تو انسانی فطرت میں ہے کہ جب
تک بار بار ایک بات کو دہرائے نہیں وہ یاد نہیں ہوتی.سُبحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى اور سُبْحَانَ رَبِّيَ
العظيم بار بار کیوں کہلوایا ایک بار ہی کافی تھا؟ نہیں.اس میں یہی سر ہے کہ کثرت تکرار اپنا ایک اثر ڈالتی
ہے اور غافل سے غافل قوتوں میں بھی ایک بیداری پیدا کر دیتی ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا.وَاذْكُرُوا الله كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (الانفال : 46 )
یعنی اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو تا کہ تم فلاح پا جاؤ.جس طرح یہ ذہنی تعلق ہوتا ہے اور کثرت
Page 270
الذكر المحفوظ
254
تکرار ایک بات کو حافظہ میں محفوظ کر دیتی ہے.اسی طرح ایک روحانی تعلق بھی ہے اس میں بھی تکرار
کی حاجت ہے.بدوں تکرار وہ روحانی پیوند اور رشتہ قائم نہیں رہتا.حضرت امام جعفر رضی اللہ عنہ
کہتے ہیں کہ میں ایک آیت اتنی مرتبہ پڑھتا ہوں کہ وہ آخروجی ہو جاتی ہے.صوفی بھی اسی طرف گئے
ہیں اور وَاذْكُرُوا اللهَ كَثِيرًا کے یہ معنے ہیں کہ اس قدرذ کر کرو کہ گویا اللہ تعالیٰ کا نام کنٹھ ہو
جائے.انبیاء علیہم السلام کے طرز کلام میں یہ بات عام ہوتی ہے کہ وہ ایک امر کو بار بار اور مختلف
طریقوں سے بیان کرتے ہیں.ان کی اصل غرض یہی ہوتی ہے کہ تا مخلوق کو نفع پہنچے.میں خود دیکھتا
ہوں اور میری کتابیں پڑھنے والے جانتے ہیں کہ اگر چار صفحے میری کسی کتاب کے دیکھے جاویں تو ان
میں ایک ہی امر کا ذکر پچاس مرتبہ آئے گا اور میری غرض یہی ہوتی ہے کہ شاید پہلے مقام پر اس نے
غور نہ کیا ہو اور یونہی سرسری طور سے گذر گیا ہو.( ملفوظات جلد چہارم صفحہ 455 تا 457)
اسی طرح اسالیب ادب کے اعتبار سے اس جگہ قرآن کریم حسنِ بیان کی اعلیٰ مثال پیش کر رہا ہے جو اپنی
مثال آپ ہے.اسالیب حسن بیان کے اعتبار سے اہلِ ادب عربی نے کلام کو تین اقسام میں تقسیم کیا ہے.1 - الاسلوب العلمی 2.الاسلوب الادبی 3.الاسلوب الخطابی
سورۃ الرحمان میں آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کو اسلوب خطابی میں شمار کیا جاتا ہے.اس اسلوب
کے بارہ میں لکھا ہے:
من اظهر المميزات هذا الاسلوب التكرار و استعمال المترادفات، و
6
ضرب الامثال و اختيار الكلمات الجزلة ذات الزنين
البلاغه الواضحه : 16)
یعنی اس اسلوب کی ممتاز خصوصیات میں تکرار ، مترادفات کا استعمال اور ضرب الامثال،
پر شوکت الفاظ، فقرات اور رقت آمیز کلمات کا استعمال شامل ہے.پس جہاں قرآن کریم اعلیٰ ترین اسالیب ادب استعمال کرتا ہے وہیں ان نام نہاد عر بی سٹائل پہنچانے والے
مستشرقین کی اصلیت مزید کھل کر سامنے آجاتی ہے.خلاصه
خلاصہ یہ کہ قرآن کریم کا ایک ایک لفظ رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی زندگی میں لکھا اور حفظ کیا گیا
حضرت ابوبکر نے اندرونی اور بیرونی شہادتوں اور ہر قسم کی گواہی کے التزام کے ساتھ ایک مجلد شکل میں پیش کیا.اس کے نزول کی ترتیب انتہائی گہری حکمتوں
کو مدنظر رکھتے ہوئے واقعات اور حالات حاضرہ کے مطابق تھی جبکہ
Page 271
قرآن کریم میں تحریف کے الزامات کے جواب
255
جمع کیے جانے کی ترتیب خدا تعالیٰ نے مقررفرمائی تھی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگرانی میں یہ ترتیب لگوائی
جس میں صحابہ کے دور میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی اور نہ ہی بعد میں
کبھی بدلی گئی.نیز یہ کہ قرآن کریم با ربط کلام ہے.جس میں ہر لفظ دوسرے لفظ سے اور ہر آیت دوسری آیت سے اور ہر سورت دوسری سورت سے ایک لڑی میں
پروئی ہوئی ہے.علاوہ ازیں اس کی معنوی ترتیب میں انسانی فطرت کے اختلاف کے پیش نظر بہت تنوع ہے.قرآن کریم کی اجزاء اور رکوعوں میں تقسیم
گزشتہ عنوان کے تحت صحیح بخاری کی یہ حدیث پیش کی گئی جس میں آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ
بن عمر رضی اللہ عنھما کو ایک ماہ میں قرآن کریم کی تلاوت مکمل کرنے کا حکم تو دیا گر قرآن کریم کو میں حصوں میں تقسیم نہ
کیا گویا یہ تقسیم امت کی صوابدید پر چھوڑ دی.بعض کے نزدیک پاروں یا اجزا میں قرآن کریم کی تقسیم کی بنیاد یہ حدیث
ہے.اسی لیے رمضان المبارک میں بھی تلاوت قرآن کا کم از کم ایک دور مکمل کرنا مستحب سمجھا جاتا ہے.مگر یہ
بہر حال ثابت ہے کہ آنحضور نے قرآن کریم کو اجزا یا پاروں میں قسیم نہیں کیا تھا بلکہ تقسیم امت کی کی ہوئی ہے.پاروں کی اس تقسیم میں فرق ہے.بعض عرب
ممالک سے چھپنے والے قرآن کریم کے نسخوں میں مثلاً مصر سے
چھپنے والے نسخہ جات میں ساتواں پارہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاس سے شروع ہوتا ہے جبکہ ہمارے ہاں چھپنے والے
نسخوں میں اس آیت سے ایک آیت بعد وَ إِذَا سَمِعُوا سے شروع ہوتا ہے.اسی طرح مصر سے چھپنے والے
نسخوں میں چودہواں پارہ المر تلک سے شروع ہوتا ہے اور ہمارے ہاں چھپنے والے نسخہ جات میں رُبَمَا
يُوَدُّ الَّذِينَ سے شروع ہوتا ہے.اسی طرح بیسویں پارے کا شروع، تئیسویں کا شروع ، اور بعض نسخوں میں
انیسویں اور چھبیسویں کے شروع میں فرق ہے مگر اس سے یہ ہر گز مراد نہیں ہے کہ قرآن کریم میں کوئی کمی بیشی
ہوئی ہے.یہ صرف اس تقسیم کا فرق ہے جو کہ الہامی نہیں بلکہ صحابہ نے یا امت نے آسانی کی خاطر کی.رکوع کی تقسیم کے بارہ میں کہا جاتا ہے کہ یہ کام حجاج کے زمانہ میں ہوا.مگر بعض روایات ایسی بھی ملتی ہیں
کہ یہ تقسیم بھی حضرت عثمان نے ہی کی تھی.(عرض الانوار: 45) بیان کیا جاتا ہے کہ پاروں کی تقسیم کی طرح نماز
تراویح کے ہر رکوع میں ایک خاص حصہ قرآن پڑھنے کے لیے ایک تقسیم کی گئی اور اسے رکوع کا نام دیا گیا.لیلتہ
القدر کے 27 رمضان تک متوقع ہونے کے لحاظ سے 27 رمضان تک تراویح میں قرآن کریم کی تلاوت مکمل کرنا
مناسب سمجھا جاتا ہے اور اس طرح قرآن کریم کو 20 رکعات روزانہ کے حساب سے 27 دنوں میں ختم کرنے کے
لیے 540 رکوعوں میں تقسیم کیا گیا.واللہ اعلم.امام ابوعمر و عثمان الوافی ، ( متوفی 444ھ ) جو اندلس کے کبار علما میں
شمار ہوتے ہیں، کا خیال ہے کہ رکوعوں کی تقسیم کا کام بھی صحابہ کر چکے تھے.(تفسير القرطبی جزو اوّل صفحه 64 از ابو عبدالله محمد بن احمد القرطبی ، متوفی
671ه ناشر دار الكاتب العربيه قاهره طبع سوم - سنا اشاعت 1967ء)
_
Page 272
الذكر المحفوظ
256
آیت رجم
کتب تاریخ میں ایسی روایات ملتی ہیں کہ ایک ایسی آیت تھی جس میں یہ حکم تھا کہ اگر بوڑھا اور بڑھیا زنا
کریں تو انہیں رجم کر دیا جائے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ آپ نے زنا
کی پاداش میں رجم کی سزادی لیکن پھر یہ آیت لفظاً منسوخ ہوگئی اور قرآن کریم میں درج نہ کی گئی مگر معنوی طور پر
منسوخ نہیں ہے.چنانچہ خلفاء راشدین نے بھی یہ سزا لا گور کھی.یہ روایات زیادہ تر حضرت عمرؓ کے حوالہ سے ملتی
ہیں کہ آپ آیت رجم کو قرآن کریم میں درج کروانا چاہتے تھے مگر ایسا نہ کر سکے.چنانچہ بخاری کی روایت ہے:
عن ابن عباس قال قال عمر لقد خشيت ان يطول بالناس زمان حتى يقول
قائل لا نجد الرجم في كتاب الله فيضلو بترك فريضة انزلها الله
(بخاری کتاب الحدودباب اعتراف بالزنا)
یعنی حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ مرورِ زمانہ
کے ساتھ لوگ یہ کہنا شروع کر دیں گے کہ ہم رجم کے احکام قرآن کریم میں نہیں پاتے اور وہ
اسے ترک کر دیں گے حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ایک فریضہ ہے.مستشرقین حفاظت قرآن پر اعتراض کرنے کی غرض سے آیت رجم کے بارہ میں روایات کو بڑی شدومد کے
ساتھ اچھالتے ہیں.چنانچہ ابن وراق اس معاملہ میں بھی اعتراض کا موقع ہاتھ نہیں جانے دیتا.کہتا ہے:
There is a tradition from Aisha the Prophet`s wife,
that there once existed a 'verse of stoning' where stoning
was prescribed as punishment for fornication, a verse
that formed a part of the Koran but that is now lost.The
early caliphs carried out such a punishment for
adulterers, despite the fact that the Koran as we know it
today, only prescribes a hundred lashes.It remains a
why Islamic law to
if the story is not true
puzzle
this day decrees stoning when the Koran only demands
flogging.According to this tradition over a hundred
verses are missing.(Ibn Warraq: Why I am Not A Muslim, The Koran: Pg 108-109)
آنحضور ( ﷺ) کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہؓ سے مروی ہے کہ کبھی ایک آیت رجم
بھی ہوا کرتی تھی جس میں زنا کی سزا رجم یعنی سنگساری مقرر تھی ، ایک آیت جو قرآن کا حصہ تھی
لیکن اب گم ہو چکی ہے.ابتدائی خلفاء نے زنا کاروں کے لیے اس قسم کی سزائیں تجویز کی تھیں،
Page 273
قرآن کریم میں تحریف کے الزامات کے جواب
257
باوجود اس کے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ آج قرآن میں صرف سو کوڑوں کی سزا کا ذکر ہے.یہ
بات ایک پہیلی بن کر رہ جاتی ہے جب ہم اس نہج سے دیکھتے ہیں کہ اگر یہ قصہ درست نہیں تو پھر
کیوں آج بھی اسلامی قانون کے مطابق رجم کا ہی فتویٰ دیا جاتا ہے جبکہ قرآن تو صرف کوڑے
مارنے کا کہتا ہے.اس روایت کے مطابق 100 سے زائد آیات گمشدہ ہیں.یہ بات قابل ذکر ہے کہ مذکورہ بالا اعتراض میں ابن وراق نے حضرت عائشہؓ سے مروی اس روایت کا تو ذکر
کر دیا مگر جان بوجھ کر حضرت عمرؓ سے مروی اسی قسم کی دوسری روایات کا ذکر نہیں کیا.حالانکہ کتب تاریخ میں رجم
کے معاملہ میں زیادہ تر روایات حضرت عمرؓ کے حوالہ سے ملتی ہیں جو زیادہ مستند اور زیادہ معروف ہیں.ابنِ وراق
کی اس حرکت کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عمرؓ کی طرف منسوب روایات کے مطالعہ سے یہ امر واضح ہو جاتا ہے کہ آپ
کے نزدیک آیت رجم قرآن کریم کا حصہ نہیں تھی.ابنِ وراق چونکہ حضرت عائشہ کی روایت کو اپنے اعتراض کی
بنیاد بناتا ہے اس لیے ہم پہلے اس روایت کا تجزیہ کرتے ہیں: کہتا ہے کہ نبی (ع) کی زوجہ محترمہ حضرت)
عائشہؓ سے مروی ہے کہ کبھی ایک آیت رجم بھی ہوا کرتی تھی جس میں زنا کی سزار جم یعنی سنگساری مقر تھی“
حضرت عائشہؓ سے مروی روایت
عن عائشة قالت لقد نزلت آية الرجم و رضاعة الكبير و لقد كان في
صحيفة تحت سريري فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم
و تشاغلنا بموته دخل داجن فاكلها
(سنن ابن ماجه كتاب النكاح باب رضاع الكبير)
یعنی حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ رجم کی آیت اور بڑے شخص کی رضاعت کے بارہ میں
آیت ایک صحیفہ میں میرے بستر کے نیچے پڑی تھی.جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی
تو ہمیں آپ کی تجہیز وتکفین میں مصروفیت کے باعث خیال نہ رہا اور پالتو بکری آئی اوروہ صحیفہ کھا گئی.اس ضمن میں عرض ہے کہ اول تو یہ بات ناممکن ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی آیت نازل ہو اور
آپ نے اس کی اشاعت نہ کی ہو.تدوین قرآن کے باب میں ہم دیکھ آئے ہیں کہ رسول
کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کسی بھی تازہ وحی کے نزول کے ساتھ ہی کا تب کو بلا کر لکھواتے اور حفاظ کو حفظ کرواتے اور اس کی کثرت سے
اشاعت ہوتی.کیسے ممکن ہے کہ رجم کی آیت نازل ہوئی ہو اور رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے اس کی
اشاعت نہ کی ہو؟ صرف حضرت عائشہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنھما کو اس کا علم ہو.حضرت عائشہ تو فرماتی ہیں:
من حدثك ان محمدا كتم شيئا مما انزل الله عليه فقد كذب والله
Page 274
الذكر المحفوظ
258
يقول "يَأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ...الآية
( بخاری کتاب تفسير القرآن باب يا أيها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك)
یعنی جس نے تجھے کوئی ایسی حدیث سنائی کہ رسول کریم نے وحی الہی میں سے کوئی آیت چھپا کر
رکھی تھی تو وہ جھوٹا ہے کیونکہ اللہ تعالی تو فرماتا ہے "يَأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ
ربِّكَ...الاية “ یعنی اے رسول جو کچھ تیرے رب نے تجھ پر نازل کیا ہے اسے آگے پہنچا دے.پس ایک طرف حضرت عائشہ یہ فتوی دے رہی ہوں جو مختلف سندوں اور ایک تو اتر کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے
اور علما کا اتفاق ہے کہ یہ فتویٰ حضرت عائشہ کا ہی ہے اور دوسری طرف ایک کمزور اور درجہ استناد سے گری ہوئی
روایت پیش کی جارہی ہو تو عقل سلیم کیا گواہی دیتی ہے کہ کون سی روایت درست تسلیم کی جائے ؟ مغربی محققین تو
حسب عادت اور اعتراض بنانے کے لیے حسب ضرورت کمز ور روایت سے ہی سہارا لیں گے.اس قسم کی روایات کے بارہ میں علامہ زمختشر می لکھتے ہیں:
و اما ما تحكى ان تلك الزيادة كانت في صحيفة في بيت عائشة
الله عنها فاكلتها الداجن فمن تاليفات الملاحدة و الروافض
رضی
(تفسیر کشاف، الجزء الثالث مقدمه تفسير سورة الاحزاب)
یعنی یہ کہنا کہ قرآن کریم میں اضافہ تھا اور وہ اس صحیفہ میں تھا جو حضرت عائشہ کے گھر میں تھا
جس کو بکری کھا گئی تو یہ تو ملاحدہ اور روافض کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں.علامہ آلوسی روح المعانی میں سورۃ الاحزاب کی تفسیر کے شروع میں لکھتے ہیں:
والحق ان من كل خبر ظاهره ضياع الشئ من القرآن الا موضوع او مؤول
(جز 20 صفحه 15 تفسير سورة الاحزاب ـ مكتبه امدادیه ملتان)
یعنی حقیقت یہ ہے کہ ہر وہ خبر جس میں قرآن کریم میں کچھ آیات یا حصوں کا ضائع ہونا بیان
کیا گیا ہے وہ یا تو گھڑی گئی ہے یا پھر اپنی جگہ سے پھیر کر بیان کی گئی ہے.یہ روایت درایت کے اصولوں کے مطابق بھی غلط ہے کیونکہ اول تو کثرت سے اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ
حضرت عمر آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر باصرار کہتے ہیں کہ انہیں رجم کے بارہ میں آیت لکھ دیں مگر آپ
اس بات کو ناپسند فرماتے ہیں.ساتھ ہی کا تب وحی حضرت زید بن ثابت بیٹھے ہیں انہیں بھی نہیں
لکھواتے(مسند احمد بن حنبل، مسند الانصار، حديث زيد بن ثابت عن النبی ﷺ اور خاموشی کے ساتھ جاکر
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو لکھوا دیتے ہیں.اور پھر سالہال سال یہ آیت تکیہ کے نیچے پڑی رہتی ہے مگر
صل الله
متن قرآن میں درج نہیں فرماتے.کیا یہ فعل رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی طرف منسوب کیا جا سکتا ہے؟
Page 275
قرآن کریم میں تحریف کے الزامات کے جواب
259
دوم یہ روایت اس لیے بھی قابل قبول نہیں کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی وفات کے بعد تو حضرت عائشہ
کے حجرہ میں ایک جم
جمگھٹا لگارہتا تھا کیوں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی وفات یہیں ہوئی تھی اور بعد از وفات
جسد اطہر بھی یہیں رکھا گیا اور یہیں صحابہ چھوٹی چھوٹی ٹولیوں کی صورت میں حاضر ہوتے اور نماز جنازہ پڑھتے اور
تدفین بھی یہیں عمل میں آئی.پس تجہیز و تکفین کے انتظامات کہیں اور تو نہیں ہورہے تھے کہ ہزاروں صحابہ
دوسرے علاقہ میں مصروف ہو گئے.صحابہ کے عشق و وفا کی مثالیں آپ دیکھ چکے ہیں.کیا ایسا ممکن ہے کہ اس
وقت صحابہ نے آپ کے جسدِ اطہر کو اس طرح اکیلا چھوڑ دیا ہو کہ بکریاں وہاں چرتی پھریں.کیا اس عورت کا قصہ
نہیں پڑھا کہ جب غزوہ احد کے بعد آنحضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی شہادت کی افواہ مدینہ میں گردش کرنے لگی تو
کیسے وہ گرتی پڑتی شہر سے باہر تک پہنچ گئی.اس کا بوڑھا باپ بچپن سے اس کا کفیل اور اس کا شوہر، جس کے
سہارے زندگی کے دکھ کاٹے اور جس کے ساتھ عمر کے سکھ دیکھے، اسی جنگ میں شرکت کرنے گئے تھے.اس کا بھائی،
اس کے بچپن سے لے کر بڑھاپے تک اس کی طاقت ، اسی جنگ میں شرکت کرنے گیا تھا.اس کے بڑھاپے کا اکلوتا
سہارا ، اس کا جواں سال بیٹا اسی جنگ میں شرکت کرنے گیا تھا.کیا وہ ان کی تلاش میں گئی تھی ؟ نہیں! وہ آنکھیں
آنے والوں میں ایک ہی چہرہ تلاش کر رہی تھیں.ہر آنے والے سے پوچھتی کہ رسول
کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
خیریت کی خبر دو! ایک کہتا ہے کہ مائی تیرا باپ شہید ہو گیا، تڑپ کر بولی.رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی تو
سناؤ! اس نے کہا تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا ، پھر وہی پکار، رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی خیریت کی خبر تو دے
دو! کہنے والے نے پھر کہا کہ تیرا خاوند بھی شہید ہو گیا مگر اس خبر نے بھی جو اس کے خرمنِ امن کو جلا کر خاکستر
کر دینے کے لیے کافی تھی ، شمع نبوت کے پروانہ پر کوئی اثر نہ کیا اور وہی ایک التجا کہ کون جیا کون مرا اس سے مجھے
سروکار نہیں.خدارا رسول خدا کی خیریت کی خبر تو دے دو! جب بتایا گیا کہ وہ بخیریت ہیں تو گویا ایک گونہ آگ
سے باہر نکل آئی اور ایک ایسی راحت و تسکین کی لہر اس کے رگ وریشہ میں سرایت کر گئی کہ بے اختیار اس کے منہ
سے نکلا: کل مصيبة بعدک جلل “ کہ آپ محفوظ ہیں تو مصائب آسان ہیں.(السيرة النبوية لابن هشام، الجزء الثالث صفحه 31 دار التوفيقة للطباعة بالازهر)
یہ تو صحابیات کی محبت کا حال تھا جنہیں آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی ذات مبارک
کو اتنا قریب سے اور اتنی کثرت
سے دیکھنے کا موقع نہیں ملا تھا جتنا مرد صحابہ کو ملا تھا.صحابہ کے غم کا اندازہ لگائیں کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی
وفات کے وقت کیا حال ہوگا.صحابہ پر تو فر ماتم سے دیوانگی کی کیفیت طاری تھی.حضرت عمر کو تو یقین ہی نہیں آرہا
کہ آنحضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم فوت بھی ہو سکتے ہیں.آپ نے شمشیر برہنہ ہاتھ میں لے کر یہ اعلان کر دیا کہ
جس نے ایسا کوئی بھی لفظ منہ سے نکالا میں اس کی گردن اڑا دوں گا.حسان بن ثابت انصاری کے اشعار بھی اسی
Page 276
الذكر المحفوظ
260
محبت کی ترجمانی کر رہے ہیں کہ:
كنت السواد لناظري فعـمــى عــلــى الــنــاظــر
کہ اے محمد یہ تو ہی تو میری آنکھوں کا نور تھا تیرے جانے سے میں تو اندھا ہوگیا
ضر
من شاء بعدک فلیمت فعلیک کنت احاض
اب تیرے بعد جو مرضی جیسے یا مرے مجھے تو تیرے ہی جانے کا خطرہ تھا
(بخاری کتاب المغازی باب مرض النبي و وفاته)
ایک طرف محبت اور فدائیت کے یہ بے نظیر نمونے اور دوسری جانب یہ حال ہے کہ نعش مبارک پڑی
ہے.اردگرد کوئی حفاظت کرنے والا بھی نہیں اور پالتو جانور آزادانہ جسدِ اطہر کے آس پاس گھوم رہے ہیں.کیا
ایسا سوچا بھی جاسکتا ہے؟
گزشتہ صفحات میں بیان کی گئی ان تفصیلات کو ذرا ذہن میں دہرائیں کہ کلام الہی کی حفاظت کا وعدہ اُس
خدائے قادر نے کس طرح پورا کیا اور آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا تعالیٰ کی توفیق سے حفاظت قرآن کے کس قدر
عظیم الشان انتظامات فرمائے تھے کہ کوئی کمی بیشی کبھی راہ نہیں پاسکی.پھر آپ کی وفات کے بعد صحابہ کا کلام الہی
کی حفاظت کے بارہ میں اختیار کیا گیا طرز عمل بھی گواہ ہے کہ حفاظت کا انتظام بے نظیر تھا.کیا صحابہ کے اس طرزِ
عمل سے کوئی ایسا شائبہ بھی پیدا ہوسکتا ہے کہ جنہوں نے مخالفتوں کے طوفان میں اپنے بوڑھے والدین ، اپنے
جواں سال بیٹوں ، اپنی جوان بیویوں، اپنے معصوم بچوں کی جانوں کو قربان کر کے الہی امانت کی حفاظت کا فرض
ادا کیا اور دنیا کو اس عدیم النظیر درجۂ استناد کے ساتھ سپرد کیا کہ اور کسی کتاب کو یہ شاندار محافظت نصیب نہ ہوئی
مگر یکا یک دنیا حیران رہ گئی کہ اس قدر بے نظیر نمونے دکھانے والی قوم کی تمام تر قربانیوں کو ایک بکری ضائع
کرگئی؟ لاحول ولا قوة الا بالله العلى العظيم ! ایس خیال است و محال است و جنوں !!!
و
پھر اس حوالہ سے بھی تو دیکھیں کہ کیا کلام الہی اس لیے اترتا ہے کہ بکری کھا جائے ؟ ایک کلام جس کو تمام عالم
کی ابدی راہنمائی کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے، جس سے انسانیت کی نجات وابستہ کر دی گئی ہے، وہ بکری کے
پیٹ میں چلا جائے؟ کیا وہ قادر و توانا خدا اپنے کلام کو ایک بکری سے نہیں بچا سکا؟ کیا اب بھی وہی خدا نہیں تھا
جس نے ایک امی بے کس کی حفاظت کا وعدہ کیا اور پھر ا سے ہزاروں مشکلات اور مصائب کی آندھیوں سے بچایا
اور اس کے قتل کی بہت سی کوششوں
کو نا کام بنایا ؟ جس نے کمزوری اور کسمپرسی کی حالت میں عظیم الشان فتوحات کا
وعدہ کیا اور پھر ہر وعدہ پورا کیا اور اس شان کی فتوحات سے نوازا کہ تاریخ انسانی میں اس کی مثال
نہیں ملتی.پس
اسی حفاظت کرنے والے اور صادق الوعد خدا نے ہی تو قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ کیا تھا پھر کیسے ممکن تھا کہ
Page 277
قرآن کریم میں تحریف کے الزامات کے جواب
261
تمام وعدے پورے کرنے والا اس معاملہ وعدہ خلافی کا مرتکب ہو جاتا ؟ اسے تو علم تھا کہ میرے کلام کے اس
حصہ کا یہ حال ہونا ہے پھر نازل ہی کیوں کیا اور اگر کر ہی دیا تھا اور ساتھ یہ وعدہ بھی کیا تھا کہ میں ہی حفاظت
کرنے والا ہوں تو پھر اس وقت یہ کون سی بکری تھی جو خدا تعالیٰ کے ارادہ کی راہ میں روک بن گئی ! ہزاروں عیار
اور خون کے پیاسے دشمن تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے اور قرآن کریم کو نقصان پہنچانے کے لیے
ایڑی چوٹی کا زور لگائیں لیکن ناکام رہ جائیں اور ایک بکری کام دکھا جائے.یہ حسرتیں اور سوچیں تو ابن وراق
اور اسی کی قماش کے لوگوں کی ہیں کہ بکریاں خدا کی تقدیر بدلنے لگیں.پس یہ روایات اور ان پر تحقیق کی بنا رکھنا
مخالفین کا محض تمسخر اور استہزاء ہے اور اس سے زیادہ ان کی کوئی حیثیت نہیں.اس کے بعد ابن وراق کہتا ہے کہ ابتدائی خلفاء نے زناکاروں کے لیے اس
قسم کی سزائیں تجویز کی تھیں،
باوجود اس کے آج جیسا کہ ہم جانتے ہیں قرآن صرف سو کوڑوں کی سزا تجویز کرتا ہے.“
صلى
الله
رسول کریم ﷺ اور خلفاء راشدین کا رجم کی سزا تجویز کرنا
یہ بات درست ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم اور خلفاء نے رجم کی سزائیں دی تھیں لیکن اس سے
بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ رجم قرآنی وحی اور اسلامی حدود میں داخل ہے بلکہ ان روایات سے واضح ہوتا ہے کہ رجم کا
حکم اصلاح معاشرہ کی خاطر جاری کیا گیا اور ایک انتظامی حکم تھا جس کا اسلامی حدود سے کوئی تعلق نہیں تھا.یہ
صرف ایک تعزیر یا ایک سزا تھی.حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:
رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم و رجم ابوبکر و رجمت ولولا
انی اكره ان ازيد فى كتاب الله لكتبته في المصحف
(ترمزی كتاب الحدود باب ما جاء في تحقيق الرجم)
رسول کریم نے رجم کی سزادی حضرت ابو بکر نے رجم کی سزادی اور میں نے بھی رجم کی سزادی.اور اگر میرے لیے کتاب اللہ میں اضافہ کرنا کراہت آمیز نہ ہوتا تو میں اسے مصحف میں درج کر دیتا.اب اس روایت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واضح اقرار موجود ہے کہ آپ کے نزدیک آیت رجم کا قرآن کریم
میں درج کیا جانا کتاب اللہ میں اضافہ کرنے کے مترادف ہے اور مکروہ ہے پس کیسے ممکن ہے کہ آپ ایسا کرتے.حضرت عمررؓ ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں:
لولا ان يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبت آية الرجم بيدى
(بخاری کتاب الاحكام باب الشهاده تكون عند الحاكم في ولايته القضاء...)
یعنی اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ لوگ کہیں گے کہ عمر نے کتاب اللہ میں اضافہ کیا ہے تو
Page 278
الذكر المحفوظ
262
میں اپنے ہاتھ سے رجم کی آیت لکھ دیتا.گویا رجم کی آیت کا قرآن میں داخل کرنا ایک قسم کا اضافہ ہے جو آپ کے نزدیک بھی اور صحابہ کے نزدیک
بھی ناپسندیدہ ہے.ان روایات میں واضح طور پر حضرت عمر یہ حقیقت بیان فرمارہے ہیں کہ آپ کے نزدیک بھی
اور صحابہ میں بھی یہ ایک جانی مانی حقیقت تھی کہ آیت رجم قرآن کا حصہ نہیں ہے اور اس کا درج کرنا دراصل قرآن
کریم میں اضافہ کرنا ہے.پس قرآن کا حصہ نہ ہونا مگر پھر بھی معاشرہ میں اس سزا کا لاگو کیا جانا یہ ثابت کرتا ہے
کہ یہ امر ریاستی اور انتظامی معاملات میں سے ایک تھا اور اسلامی حدود سے اس کا تعلق نہیں تھا.جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ حضرت عمر نے یہ کیوں فرمایا کہ میں خود اپنے ہاتھ سے
لکھ دیتا تو اس سے صرف
یہ واضح ہوتا ہے کہ حضرت عمر کے نزدیک رجم کے حکم کی اہمیت اتنی زیادہ ہے.ورنہ حضرت
عمر رضی اللہ عنہ کا دل قرآن
کریم کے بارہ میں کس قدر حساس تھا اس کا نمونہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ کس طرح پڑھنے کے انداز میں ادنیٰ سے اختلاف
پر آپ بھرے ہوئے شیر کی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں اور قرآن کریم کی حفاظت کے میدان میں کسی کی بھی پروا
نہیں کرتے.پس کیسے ممکن ہے کہ آپ قرآن کریم میں کوئی اضافہ کرنا چاہتے ہوں؟ چنانچہ دوسری روایات میں یہ ذکر
بھی ملتا ہے کہ آپ فرماتے کہ میں اس حکم کو قرآن کریم کے حاشیہ پرلکھ لیتا.مثلاً روایت ہے:
ولولا ان يقول القائلون زاد عمر في كتاب الله ما ليس منه لكتبته في
ناحية من المصحف
(مسند احمد بن حنبل مسند العشرة المبشرين بالجنه مسند عمر بن الخطاب)
اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ کہنے والے کہیں گے کہ عمر نے کتاب اللہ میں ایسا اضافہ کر دیا ہے جو کہ
دراصل اس کے متن کا حصہ نہیں ہے تو میں یہ حکم کتاب اللہ کے حاشیہ پر لکھ دیتا.اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ آپ اس حکم کو قرآن کریم کے متن کا حصہ نہیں سمجھتے تھے بلکہ فرمارہے ہیں کہ
اگر میں لکھتا بھی تو بطور حاشیہ لکھتا تا کہ یہ بھی قرآن کریم کے ساتھ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے لیکن اس لیے نہیں
لکھا کہ ایک طرف رسول کریم کی واضح ممانعت ہے کہ قرآن کریم کے متن کے ساتھ کوئی دوسری عبارت درج نہ
کی جائے اس لیے مجھے یہ امر کر وہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے واضح فرمان کو ٹالتے ہوئے قرآن کریم کے متن کے ساتھ
کچھ لکھوں.یہ ذکر بھی گزر چکا ہے کہ صحابہ نے اپنے نسخوں میں جو تشریحی تحریرات درج کی ہوئی تھیں، حضرت عمرؓ نے
رسول کریم کے ایک ارشاد اور سنت سے رہنمائی لیتے ہوئے ان تمام تشریحی تحریرات اور حواشی کو تلف کرادیا تھا.اگر
آپ رجم کا حکم حاشیہ میں بھی درج کرتے تو یہ اعتراض بھی ہوتا کہ خود تو حاشیہ میں ایسی تحریرات لکھ رہے ہیں اور دیگر
حابہ سے کہتے ہیں کہ ایسی تحریرات جن میں قرآنی آیات کے ساتھ تشریحی حواشی درج ہیں تلف کر دی جائیں.
Page 279
قرآن کریم میں تحریف کے الزامات کے جواب
263
حضرت عمرؓ کے علاوہ دیگر صحابہ نے بھی رجم کا ذکر کیا ہے لیکن کبھی یہ نہیں کہا کہ رجم کا حکم قر آنی تھا.بلکہ اسے
سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی سمجھتے تھے.چنانچہ کا تب وحی حضرت زید نے یہ آیت قرآن
کریم میں نہیں لکھی بلکہ یہ
فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کو رجم کرنے کا حکم دیتے ہوئے سنا: چنانچہ روایت ہے کہ:
قال زيد سمعت رسول الله ﷺ يقول الشيخ و الشيخة اذا زنيا
فارجموهما البتة فقال عمر لما انزلت هذه أتيت رسول الله صلى الله
عليه وسلم فقلت اكتبنيها قال شعبة فكأنه كره ذلك.صلى الله.(مسند احمد بن حنبل، مسند الانصار، حدیث زید بن ثابت عن النبي ( لا )
یعنی زید کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کو ایسا کہتے ہوئے سنا کہ جب
ایک بوڑھا شخص اور بڑھیاز نا کریں تو انہیں رجم کر دیں حضرت عمرؓ کہتے ہیں کہ جب یہ حکم ہوا
تو میں رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ یہ مجھے لکھ کر دے
دیں.اس پر آپ نے کراہت کا اظہار فرمایا.پس اسی روایت میں ایک اور اندرونی گواہی اس بات پر ہے کہ آیت رجم متن قرآن کریم کا حصہ نہیں ہے.حضرت زید فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم کو ایسا کہتے ہوئے سنا.یعنی آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی
خدمت میں موجود تھے اور آپ نے عام حدیث کے انداز میں ایک بات سنی جو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم
نے لکھنے کا حکم نہیں دیا اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم لکھوانا بھول گئے ہوں کیونکہ اسی حدیث میں
ذکر ہے کہ جب حضرت عمر نے لکھنے کی درخواست کی تو آپ نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا.گویا یہ آپ کے اسی حکم
لا تكتبوا عنى سوى القرآن یعنی مجھ سے قرآن کے سوا کچھ نہ لکھو(مسند احمد بن حنبل کتاب الباقی
مسند المكثرين باب مسند ابی سعید الخذریم) کے تحت آتا تھا اور یہ سوی القرآن تھی.جو کا تب وحی کونہ
لکھوائی گئی.پس حضرت عمر کو کیوں لکھ کر دی جاتی ؟
حضرت عمر کا یہ کہنا کہ یہ آیت مجھے لکھ کر دی جائے بھی اس بات
کو واضح کرتا ہے کہ آپ جانتے تھے کہ یہ
قرآنی وحی نہیں ہے.ورنہ قرآنی وحی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم ہر ایک کو لکھ کر نہیں دیا کرتے تھے صرف
کاتبین کو لکھواتے تھے.نیز آنحضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی طرف سے قرآنی وحی لکھ لینے کی واضح اجازت موجود
تھی.صحابہ خود اپنے لیے وحی تحریر کیا کرتے اور ان تحریرات کو آنحضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے سامنے پیش کر کے
ان کے صحیح ہونے کی تصدیق کروا لیتے.حضرت
عمر تو لکھنا پڑھنا بھی جانتے تھے.اگر واقعی قرآن کریم کی ایسی
کوئی آیت تھی تو کیوں
نہ خود لکھ لی؟ پس لازماً آپ بھی اسے سوی القرآن سمجھتے تھے اور اس کا بلا اجازت لکھنا
Page 280
الذكر المحفوظ
264
اس حکم لا تكتبوا عنی سوی القرآن کی نافرمانی سمجھتے تھے تبھی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت
لے رہے تھے کہ اس بات کی مجھے تحریر دے دی جائے.ورنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے قرآن کریم کا
کوئی بھی حصہ لکھنے سے تو کبھی منع نہیں فرمایا اور نہ ایسا کرنے والے کے خلاف کراہت کا اظہار فرمایا.مختصر یہ کہ حضرت عمر کا اجازت لینا، رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی ناپسندیدگی اور کاتب وحی کے ساتھ
ہی موجود ہونے کے باوجود انہیں نہ لکھوانا اس بات پر شاہد ناطق ہے کہ یہ حکم قرآن کریم کی آیت نہیں بلکہ
معاشرتی اور انتظامی امور کے لیے ایک عمومی حکم دیا گیا ہے اور حضرت عمر بھی ما لیس منہ کے الفاظ سے یہ واضح
فرمارہے ہیں کہ اُن کے نزدیک بھی یہ قرآن کریم کا حصہ نہیں ہے.یہ بھی یادر ہے کہ حضرت عمرؓ تو حضرت ابو بکڑ کے عہد خلافت میں ہونے والی تدوین قرآن میں اہم اور کلیدی
کردار ادا کر رہے تھے.اگر کوئی ایسی آیت تھی تو اس آیت پر تو آپ اور حضرت عائشہ دو گواہ موجود تھے.چنانچہ اگر
آپ واقعی رجم کے حکم کو وحی قرآن کا حصہ سمجھتے تھے تو ضرور اسے قرآن کریم میں درج فرماتے.مگر ایسا نہ کرنا ثابت
کر دیتا ہے کہ آپ اسے اس لحاظ سے الہی راہنمائی سمجھتے تھے کہ تو رات میں اس کا ذکر تھا اور آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم
نے بطور نگران اعلیٰ یا ایک ریاست کے حاکم ہونے کے حیثیت سے اسے معاشرہ پر لا گو بھی کیا تھا.لیکن یہ امر بھی
واضح ہے کہ قرآن کریم ایک کامل تعلیم ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک اس میں رجم کے بارہ میں
کسی تعلیم کا نازل
نہ ہونا یہ ثابت کرتا ہے کہ قرآن کریم کی آفاقی اور عالمی تعلیم میں اس حکم کی گنجائش نہیں تھی اور یہ
روایات بھی ملتی ہیں کہ حضرت عمر پڑھنا لکھنا جانتے تھے اور تورات کا بھی مطالعہ کرتے رہتے تھے.(مشکواۃ کتاب
الاعتصام بالكتاب و السنة) اگر واقعی آپ ان احکام کو قرآنی وحی کا حصہ سمجھتے تھے تو یہ ایک غلطی تھی.(تفسیر کبیر جلد
6 صفحہ 251 کالم 2 زیرتفسیر آیت سورۃ النور :1 تا3) دوسری یہ صورت بھی ہو سکتی ہے کہ اُس دور میں ریاست کے
نگران اعلیٰ کی طرف سے لاگو کی گئی ایک سزا کو حضرت عمر کی طبیعت نے اصلاح معاشرہ کے لیے بہت سراہا اور
اسے لمبے عرصہ تک جاری رکھنے کی کوشش کی تاکہ معاشرہ سے زنا کی لعنت کو ختم کیا جاسکے.یہ بھی ایک معروف
حقیقت ہے کہ حضرت عمر کی طبیعت میں ایک قسم جلال پایا جاتا تھا.آپ اس خوبصورت معاشرہ کے فرد تھے جو
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے انتہا قربانیوں اور بہت سی مشقتوں کے بعد پروان چڑھایا تھا.اس میں ادنی سی دراڑ
یا بدصورتی کی کوشش کو آپ کس طرح برداشت کر سکتے تھے؟ بہر حال رجم کے حق میں آپ کی طبیعت کے میلان کی جو
بھی وجہ ہو، یہ بات بھی تاریخ سے بالکل واضح ہے کہ آپ بہر حال رجم کے
احکام کو قر آنی تعلیم سے باہر ہی سمجھتے تھے.رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے اسوہ کا مطالعہ کرتے وقت یہ مد نظر رکھنا ضروری ہے کہ مدینہ کے دور
میں آپ نہ صرف ایک رسول تھے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک حاکم اور ایک عالمی قاضی کی حیثیت سے بھی دُنیا
Page 281
قرآن کریم میں تحریف کے الزامات کے جواب
265
کے سامنے تھے.پس آپ کے فیصلوں کا مطالعہ کرتے ہوئے یہ بات مدنظر رکھنی ضروری ہے کہ کون سے فیصلے
اسلامی شریعت کے مطابق ہیں اور کون سے ایک حاکم ہونے کی حیثیت میں ہیں اور کون سے فیصلے ایک
عالمی قاضی ہونے کی حیثیت سے دیے جارہے ہیں جو کہ متفرق قوانین کے تابع ہیں اور اسلامی حدود کے دائرہ
میں نہیں آتے.پھر یہ بات بھی مد نظر رکھنی ضروری ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم بعض دفعہ فیصلہ کرتے ہوئے
بطور حاکم اصلاح احوال مدنظر رکھتے تھے اور ایسا فیصلہ دائمی نوعیت کا نہیں ہوتا تھا.حضرت مسیح موعود علیہ السلام
ابتدائی دور میں رجم کی سزا دینے کی حکمت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:
" یہودیوں کی مقدس کتاب اور اسلام کی مقدس کتاب کی رُو سے یہ عقیدہ متفق علیہ مانا گیا
ہے کہ جو شخص ایسا ہو کہ خدا کی کتابوں میں اُس پر ملعون کا لفظ بولا گیا ہو.وہ ہمیشہ کے لئے خدا
کی رحمت سے محروم اور بے نصیب ہوتا ہے.جیسا کہ اس آیت میں بھی اشارہ ہے.مَلْعُونِينَ.أَيْنَمَا تُقِفُوا أُخِذُوْاوَ قُتِلُوا تَقْتِيلاً [ الاحزاب :62] یعنی زنا کار اور زنا کاری کی اشاعت
کرنے والے جو مدینہ میں ہیں لعنتی ہیں.یعنی ہمیشہ کے لئے خدا کی رحمت سے رڈ کئے گئے.اس لئے یہ اس لائق ہیں کہ جہاں انکو پاؤو قتل کر دو.پس اس آیت میں اس بات کی طرف یہ
عجیب اشارہ ہے
کہ لعنتی ہمیشہ کیلئے ہدایت سے محروم ہوتا ہے اور اس کی پیدائش ہی ایسی ہوتی ہے
جس پر جھوٹ اور بدکاری کا جوش غالب رہتا ہے.اور اسی بنا پر قتل کرنے کا حکم ہوا.کیونکہ جو
قابل علاج نہیں اور مرض متعدی رکھتا ہے اس کا مرنا بہتر ہے.اور یہی تو ریت میں لکھا ہے کہ
66
لعنتی ہلاک ہو گا.“
تریاق القلوب روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 237 ،238)
رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا اسوہ یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ نے کبھی بھی رجم کو اسلامی شرعی حد نہ قرار دیا
بلکہ رجم کے بارہ میں آپ
کا اسوہ اور رویہ شرعی حدود کے بارہ میں آپ کے رویہ سے بالکل مختلف تھا.رجم کی سزا
کے بارہ میں یہ روایت ملتی ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص ماعز بن مالک کو آپ نے رجم کی سزا دی.جب اسے رجم کیا
جار ہا تھا تو وہ پتھر لگنے پر بھاگ کھڑا ہوا.صحابہ نے تعاقب کر کے اسے پکڑ لیا اور سنگسار کر دیا.جب اس واقعہ کا
رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کوعلم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اگر وہ بھاگ رہا تھا تو بھاگنے دیتے.ہوسکتا ہے کہ وہ
تو بہ کرتا اور اللہ اس کی توبہ قبول فرمالیتا (بخاری کتاب الحدود باب رجم ماعز بن مالك ) - گویا رجوع یا تو بہ
کرنے پر آپ اس سزا میں تخفیف یا اسے بالکل ہی کالعدم کرنے کے حق میں تھے.لیکن اسلامی حدود کے حوالہ
سے آپ کے طرز عمل کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے بعید تھا
کہ قرآن کریم میں ایک واضح حکم موجود ہو اور آپ اس کی پیروی نہ کریں.شرعی حدود کے بارہ میں تو آپ کا فتویٰ
Page 282
الذكر المحفوظ
266
موجود ہے کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں ضرور اس کا ہاتھ کا تھا.(بخاری کتاب المناقب باب ذکر
اسامہ بن زید ) اس میں جرم ثابت ہونے کے بعد تو بہ کا سوال ہی نہیں.کیونکہ اب تو سزا کا وقت ہوتا ہے.اب
اگر رجم کی سزا بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ اور اسلامی حدود میں سے ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم
کس طرح اس میں تخفیف کر سکتے تھے؟ پس قرآن کریم میں رجم کی سزا کسی بھی وقت موجود نہیں رہی.رجم کا ذکر
توریت میں ملتا ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے اپنے دور میں یہود میں فیصلے کرتے ہوئے تو ریت
کے مطابق ہی ارشادات جاری فرمائے اور پھر اُس دور میں مدینہ کے ماحول کے مطابق اس سزا کولا کو کیا مگر شرعی
حد کے طور پر نہیں بلکہ آپ کا طرز عمل یہی تھا کہ جب تک کوئی نئی الہی راہنمائی نہیں آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم
توریت کے مطابق فیصلہ کرتے.چنانچہ معاشرتی اور سماجی اصلاح کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک سزا
مقرر فرمائی جو یہود کے لیے تو شرعی حد ہی تھی مگر باقی لوگوں کے لیے محض ریاست کی طرف سے مقرر کی گئی ایک
تعزیر تھی.جس طرح ریاست کی مقرر کردہ سزا میں ریاست تخفیف کر سکتی ہے یا اس سزا کو معاف بھی کر سکتی ہے اسی
طرح رسول
کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست کا نگران اعلیٰ ہونے کے حوالہ سے یہ فرمایا کہ جب ایک شخص کا
رجوع کرنا ظاہر ہورہا تھا تو اسے چھوڑ دیتے کیونکہ وہ یہودی نہیں تھا اس لیے اُس کے لیے یہ سزا شرعی حد نہیں تھی
لیکن اسلامی شرعی حدود کے معاملہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دینے یا تخفیف کرنے کا اختیار نہ تھا
جیسا کہ اس حدیث میں ذکر ہے جس میں چور کو ہاتھ کاٹنے والی سزادی تھی.(بخاری کتاب المناقب باب ذکر اسامه بن زید)
باب اسماء
حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب خلیفتہ امسیح الثانی المصلح الموعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:
پس یہ ایک ثابت شدہ حقیقت ہے کہ قرآنی حکم یہی ہے کہ اگر کسی عورت یا مرد سے زنا صادر
ہو جائے تو اس کو سو (100) کوڑے لگائے جائیں.لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے
بائبل کی تعلیم کے مطابق اپنے استدلال سے یہودی مذہب کی سزا کو پہلے جاری کیا اس کے بعد
چونکہ قرآنی حکم نازل ہو گیا اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے حکم کو ہم محض عارضی حکم
کہیں گے مستقل حکم نہیں کہیں گے کیونکہ مستقل حکم آپ کا وہی ہوتا ہے جس کے متعلق قرآنی حکم
موجود نہ ہو.اس کا ثبوت اس طرح بھی ملتا ہے کہ رسول کریم نے شروع میں قبلہ بھی
یہودیوں کے طریق کے مطابق بیت المقدس کو ہی رکھا تھا.لیکن جب قرآن کریم میں یہ حکم
نازل ہوا کہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کیا جائے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے بیت
اللہ کی طرف منہ کر لیا.چنانچہ دوسرے پارے کے شروع میں اس کا ذکر آتا ہے.اسی
Page 283
قرآن کریم میں تحریف کے الزامات کے جواب
267
طرح احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ بعض دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم قوم کی
اصلاح کے لیے ایک حکم فرما دیا کرتے تھے لیکن وہ دائی حکم نہیں ہوتا تھا.مثلاً بخاری میں ہی آتا
ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے پاس ایک دفعہ وفد عبدالقیس آیا اور اُس نے کہا یا
رسول اللہ ! ہمیں کوئی خاص ہدایت دیجیے.آپ نے فرمایا.فلاں فلاں چار قسم کے برتن استعمال
نہ کیے جائیں (بخاری کتاب الایمان باب اداء الخمس من الايمان) ليكن قريباًسب
مسلمان آج اُن برتنوں کو استعمال کرتے ہیں اور سب فقہاء کہتے ہیں کہ یہ برتن جائز ہیں اور اس
کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ اُن لوگوں میں رواج تھا کہ اس قسم کے برتنوں میں وہ شراب بناتے
تھے.رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے اُن کی اس عادت کو چھڑانے کے لیے حکم دے دیا کہ
یہ برتن استعمال نہ کیا کرو.ان برتنوں کے استعمال نہ کرنے کی وجہ سے شراب بنانے کی عادت
اُن میں سے جاتی رہی اور بعد میں تمام مسلمانوں کے اتفاق کے مطابق یہ حکم غیر ضروری ہو گیا
اور اس قسم کے برتنوں کا استعمال سب مسلمانوں کے لیے جائز ہو گیا.حدیثوں سے یہ بات ثابت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے رجم کا حکم محض
یہودی احکام کی اتباع میں دیا تھا.( تفسیر کبیر جلد 6 صفحہ 255 کالم 1 زیرتفسیر آیت النور :3 )
ایک سوال یہ اُٹھ سکتا ہے کہ جب یہ شرعی حد نہیں تھی اور آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تخفیف یا معافی کے
مجاز تھے تو پھر جب ایک معاملہ میں یہود نے ، جب کہ آپ رجم کی سزا دے رہے تھے، پس و پیش کی تو آپ نے
کیوں انہیں معاف نہیں کیا یا ان کی سزا میں تخفیف نہیں کی ؟
اس کا جواب یہ ہے کہ اول تو یہود کے لیے یہ معاملہ شرعی حد کا ہی تھا.کیونکہ ان کی شریعت کی کتاب میں زنا کی
یہی سزا درج ہے اس لیے آپ یہود کے معاملہ میں جب کہ ان کا مطالبہ بھی یہی تھا کہ کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ
کریں آپ یہی فیصلہ کر سکتے تھے اور اس میں
کمی بیشی کے مجاز نہیں تھے.چنانچہ یہود کے اس معاملہ میں آپ نے
انہی کے مطالبہ پر ان کی شرعی کتاب کے مطابق فیصلہ کیا تھا.پس وہ فیصلہ آپ کا نہیں بلکہ ان کی شریعت کا تھا.آپ
صرف اس بات کے مجاز تھے کہ اپنی نگرانی میں اسے لاگو کر دیں.اس سے بڑھ کر آپ کے پاس اختیار نہ تھا.اگر یہود کے لیے یہ معاملہ شرعی نہ بھی ہوتا تو بھی آپ کے اس فیصلہ پر اور نہ ہی کسی اور فیصلہ پر اعتراض نہیں
ہو سکتا ہے کیونکہ جب منصف ایک فیصلہ کرتا ہے تو اس کے سامنے بہت سے امور ہوتے ہیں اور وہ جرم کی نوعیت،
مجرم کی حالت اور مدعی کے دعوئی اور دلائل اور حالات و واقعات کو مد نظر رکھ کر فیصلہ دیتا ہے.پندرہ سو سال گزرنے کے
Page 284
الذكر المحفوظ
268
بعد، جبکہ اس وقت پیش نظر حکمتیں اور مکمل حالات و واقعات ہمارے علم میں نہیں اس لیے اعتراض کرنا فضول ہے.پس آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست کے نگران اعلیٰ ہونے کی حیثیت سے بطور تعزیر تورات کے اس حکم کو
لاگو کیا مگر اپنے اسوہ سے یہ بھی بتلا دیا کہ یہ حکم مل بھی سکتا ہے جبکہ اسلامی حدود کے بارہ میں آپ کا طرز عمل اس
امر کو واضح کرتا ہے کہ مجرم ثابت ہونے کے بعد اسلامی حدود میں کسی قسم کی نرمی نہیں کی جاسکتی.خلفاء راشدین
نے بھی اس حکم کو اصلاح معاشرہ کے لیے لاگو رکھا.چنانچہ حضرت علی بھی رحم کو سنتِ رسول صلی اللہ علیہ والہ وسلم
سمجھتے تھے نہ کہ وحی الہی.چنانچہ روایت میں ہے کہ ایک دفعہ ایک زنا کے مقدمہ میں ایک عورت کو کوڑے بھی
لگوائے اور رجم بھی کیا اور فر مایا کہ:
جلدتها بكتاب الله و رجمتها بسنة رسول الله ﷺ
(بخارى كتاب الحدود باب رجم المحصن)
یعنی میں نے اس عورت کو کتاب اللہ کی تعلیم کے مطابق کوڑے لگوائے ہیں اور رجم
رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی سنت کی اتباع میں کیا ہے.الغرض رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی سنت کی اتباع میں، نیز معاشرہ کی اصلاح کے لیے وقت کی
ضروریات اور حالات کے مطابق خلفاء راشدین نے بھی رجم کی سز ا بطور تعزیر لا گورکھی جو قابل اعتراض نہیں ہے.حضرت عائشہ کی طرف منسوب روایت کے حوالہ سے اُٹھائے ہوئے اعتراض کے آخر میں ابن وراق کہتا
ہے کہ اس روایت کے مطابق 100 سے زیادہ آیات گم شدہ ہیں:
اس کے جواب میں ہم روایت کے الفاظ درج کر دیتے ہیں:
عن
عائشة قالت لقد نزلت آية الرجم و رضاعة الكبير عشرا و لقد
كان في صحيفة تحت سريرى فلما مات رسول الله صلى الله عليه و
سلم و تشاغلنا بموته دخل داجن فاكلها
(سنن ابن ماجه كتاب النكاح باب رضاع الكبير)
یعنی حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ رجم کی آیت اور بڑے شخص کی رضاعت کے بارہ میں
آیت ایک صحیفہ میں میرے بستر کے نیچے پڑی تھی.جب رسول کریم کی وفات ہوئی تو ہمیں آپ
کی تجہیز و تکفین میں مصروفیت کے باعث خیال نہ رہا اور پالتو بکری آئی اور وہ صحیفہ کھا گئی.پس اگر اس کے علاوہ حضرت عائشہ سے منسوب کسی روایت میں جس میں رجم کا ذکر کرتی ہیں 100 گمشدہ آیات
کا بھی ذکر ہو تو وہ بیان کی جائے.جب تک وہ روایت نہیں ملتی ہم لعنۃ اللہ علی الکاذبین ہی کاورد کر سکتے ہیں.
Page 285
قرآن کریم میں تحریف کے الزامات کے جواب
269
اختلاف مصاحف
نزول قرآن کے دور میں عرب میں نہ تو لکھنے کا عام رواج تھا اور نہ ہی صحابہ عام طور پر آداب تحریر سے واقف
تھے.علاوہ ازیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ پر یہ ذمہ داری عائد بھی نہیں کر رکھی تھی کہ قرآن کریم
لازماً تحریر کیا کریں البتہ کسی کو قرآن کریم تحریر کرنے سے روکا بھی نہیں تھا بلکہ آپ کے فرمودات سے معلوم ہوتا
ہے کہ آپ اس بات کی حوصلہ افزائی فرماتے کہ مسلمانوں کے پاس قرآن کریم کی تحریرات کثرت سے ہوں.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصائح پر اطاعت کے اعلیٰ نمونے دکھاتے ہوئے صحابہ قرآن کریم کا کچھ نہ کچھ حصہ
تحریر کر کے اپنے پاس رکھتے تھے.مگر عام طور پر صحابہ با قاعدہ مکمل قرآن مجید تحریر نہیں کیا کرتے تھے.بلکہ کسی نے
کچھ حصہ لکھا ہوتا تھا اور کسی نے کچھ حصہ اور جس قدر لکھتے بھی تو ذاتی ضرورت کے مطابق اور ذاتی استعمال کی
غرض سے لکھتے.چنانچہ بعض صحابہ نے وہ مشہور سورتیں جو ہر چھوٹے بڑے مسلمان کو حفظ تھیں، اپنے مصاحف
میں درج نہ کیں.پھر صحابہ اپنی یادداشت کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان فرمودہ کوئی تشریحی کلمہ یا
جملہ بھی حاشیہ کے طور پر قرآن کریم کے متن کے ساتھ ہی لکھ لیتے اور یہ علم عام ہوتا تھا کہ یہ حصہ قرآن کریم کے متن
کا حصہ نہیں ہے.کیونکہ کثرت سے لوگوں کو قرآن کریم حفظ تھا اور قرآن
کریم کی تعلیم عام تھی.چنانچہ حضرت عائشہ
کے ایک غلام ابی یونس کا ذکر ملتا ہے آپ حضرت عائشہ کے لیے قرآن کریم کی آیات تحریر کیا کرتے تھے.آپ
نے حضرت عائشہؓ کے کہنے پر حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَ الصَّلوةِ الوُسُطى (البقرة: 239) کے ساتھ بطور
تفسیر کے یہ جملہ درج کیا تھا و صلوة العصر “ ( ترمذی ابواب تفسير القرآن عن النبي ﷺ باب و من
سورة البقرة ) اس روایت سے واضح ہے کہ و صلوۃ العصر “ کے الفاظ تشریحی ہیں.چنانچہ تمام حفاظ کا سکوت
اس پر گواہ ہے.پھر عام طور پر صحابہ کو بھی یہ علم تھا کہ یہ الفاظ متن قرآن کا حصہ نہیں بلکہ تشریح کے لیے بطور
حاشیہ درج کیے گئے ہیں.چنانچہ حضرت عبد اللہ بن مسعود اور ایک اور صحابی کی حدیث میں یہ ذکر ہے کہ
آنحضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے بیان
فرمایا کہ صلوة الوسطی سے مراد صلوۃ العصر ہے.گویا واضح
کر رہے ہیں کہ یہ آنحضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی بیان فرمودہ ایک تفسیر ہے نہ کہ قرآنی الفاظ.(ترمذی ابواب
تفسير القرآن عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم باب و من سورة البقرة ) امام ترمذی کا دونوں
احادیث کو باب تفسیر میں لانا اس بات کا بین ثبوت ہے کہ علما کو علم تھا کہ آیت کون سی ہے اور تشریح کون سی.پھر
صحابہ اس بات کا بھی خیال رکھتے تھے کہ ان کے مصاحف انہی کے پاس رہیں تاکہ ناواقف شخص کو ان سے ٹھوکر نہ
لگے یا ان میں درج تفسیری نکات کو دوسرا شخص متن قرآن نہ سمجھ بیٹھے.چنانچہ جب حضرت عائشہ سے ایک صحابی
Page 286
الذكر المحفوظ
270
نے ان کا نسخہ قرآن مانگا تو حضرت عائشہؓ نے پس و پیش کیا.(بخاری کتاب جمع القرآن باب تاليف القرآن)
ڈاکٹر صبحی صالح اپنی کتاب علوم القرآن میں اس ضمن میں ایک دوسری مثال پیش کرتے ہیں:
بعض صحابہ نے اپنے ذاتی نسخوں میں بعض آیات کی وہ تفسیر بھی رقم کر رکھی تھی جو انہوں نے
بذات خود آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی.اس کی مثال یہ ہے کہ آیت قرآنی: لیس
عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِّنْ رَّبِّكُمُ میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓا اپنے ذاتی نسخہ میں
في مواسم الحج “ کے الفاظ بڑھا لیا کرتے تھے جس کا مطلب ہے کہ اس آیت میں
اجازت دی گئی ہے کہ حج کے دنوں میں تجارت کر کے مالی فائدہ اُٹھایا جاسکتا ہے.اس میں شبہ
نہیں کہ یہ الفاظ ایضاح و تفسیر کے لیے لکھے گئے تھے کیونکہ قرآن کریم کے جس نسخہ پر امت کا
اجماع ہوا ہے اس میں یہ الفاظ نہیں ہیں.ابن الجرزی اس پر روشنی ڈالتے ہوئے فرماتے ہیں:
و بعض اوقات تفسیری کلمات کو ایضاح و تفسیر کے لیے قراءت میں شامل کر لیا جاتا تھا اس
لیے کہ صحابہ نے بذات خود آنحضور سے قرآن سُنا تھا.بنا بریں انہیں یہ خطرہ لاحق نہ تھا کہ تفسیری
کلمات قرآنی الفاظ کے ساتھ مخلوط ہو جائیں گے.بعض صحابہ تفسیر پر مشتمل الفاظ کو اپنے ذاتی
نسخہ میں لکھ لیا کرتے تھے.مثلاً حضرت عائشہ نے ایسا کیا ہوا تھا.“
( بار چہارم 1993 : باب دوم فصل اول ، عہد عثمان میں جمع تدوین، صفحہ 123)
تحریر کا عام رواج نہ ہونے کی وجہ سے لکھنے والوں کو آداب تحریر سے گہری واقفیت بھی نہیں تھی اور نہ ہی عام طور
پر لوگ پڑھنا جانتے تھے.اس لیے نا واقف انسان کے لیے سمجھنا مشکل ہو سکتا تھا کہ قرآن کریم کی آیت کہاں
تک ہے اور کہاں سے حاشیہ شروع ہوتا ہے اسی لیے آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم دے دیا تھا کہ قرآن کریم کی
تحریر کو محفوظ کرنے کی خاطر اُن کے ساتھ آنحضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے اقوال کو نہ لکھا جائے تا کہ خلط ملط
ہونے کا اندیشہ نہ رہے.چنانچہ آپ نے ایک مرتبہ اپنی حیات مبارکہ میں ہی ایسی تحریرات نذر آتش کروادی تھیں
جن میں آپ کے فرمودات تحریر کیے گئے تھے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باریک بین نظر
نے دیکھ لیا تھا کہ ایسی تحریرات جن میں قرآن کریم کی آیات کے ساتھ تفسیر کے طور پر آپ کے فرمودات درج
ہیں شک کا باعث بن سکتی ہیں.اس فرمان اور سنت کے مطابق حضرت عمرؓ نے اپنے عہد خلافت میں اس قسم کی
تحریرات کو تلف کرا دیا تھا تا کہ کسی قسم کا کوئی شک پیدا نہ ہو.(عبد الصمد صارم الازھری : تاریخ القرآن، ایڈیشن
1985 ندیم یونس پرنٹرز لاہور، پبلشرز : مکتبہ معین الادب اردو بازار لاہور صفحہ 104) پھر صحابہ اپنے اپنے قبیلہ کی
قراءت کے مطابق قرآن لکھتے تھے اور یہ بھی رسول کریم کی اجازت سے تھا.ایک ناواقف انسان اس سے بھی
Page 287
قرآن کریم میں تحریف کے الزامات کے جواب
271
ٹھوکر کھا سکتا ہے.پھر یہ مصاحف چونکہ صحابہ اپنے ذاتی استعمال کی غرض سے لکھ رہے تھے اس لیے بعض انہیں
سورتوں کو لکھتے جن کو لکھنے کی وہ ضرورت محسوس کرتے یا پھر برکت کی خاطر وحی قرآن کا کچھ حصہ نزول کے ساتھ
ساتھ لکھ لیتے تھے.پھر وحی کے جاری ہونے کی وجہ سے قرآن کریم کے متن کی تحریر میں ظاہری ترتیب کو قائم رکھا
ہی نہیں جاسکتا تھا نیز ترتیب کا عام علم ہونے کی وجہ سے متن کو ظاہری ترتیب کے ساتھ تحریر کرنے کی کوئی خاص
ضرورت محسوس بھی نہیں کی جاتی تھی.یہ ترتیب تو اس وقت سامنے آسکتی تھی جب قرآن مکمل ہو کر کتابی شکل
میں جمع اور پیش کیا جاتا جو کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ میں ناممکن تھا.علاوہ ازیں تمام صحابہ اس
بات سے بخوبی واقف تھے کہ قرآنِ کریم کا مرکزی صحیفہ تمام تر احتیاط کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
نگرانی میں تکمیل کے مراحل طے کر رہا ہے اس لیے برکت کے لیے اور حسب ضرورت عام طور پر صحابہ کچھ حصہ
قرآن تو تحریری صورت میں اپنے پاس رکھتے مگر مکمل نسخہ تحریر کرنے کی ضرورت نہ سمجھتے.پس صحابہ کا اپنے طور پر
مصاحف جمع کرنا رضائے الہی اور اپنی ذاتی ضرورت کے لیے ہوتا تھا.اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں تھی.خصوصاً اس صورت میں جبکہ رسول
کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے زیر نگرانی جمع و تدوین کا کام بھی ہورہا تھا اور تعلیم
قرآن کا سلسلہ بھی زور وشور سے جاری تھا.حضرت ابو بکر نے اپنے دور خلافت میں صحابہ کرام کی متفقہ گواہی سے قرآن کریم کا ایک نسخہ تحریر کر کے محفوظ
کر دیا تھا.جسے مصحف ام کہا جاتا ہے.مصحف ام کی وجہ سے صحابہ کرام کی متفرق اور ذاتی طور پر تیار کی گئی
تحریرات کے فرق کی وجہ سے آئندہ جو شبہات پیدا ہو سکتے تھے ان کا خطرہ ٹل گیا.تمام صحابہ نے یہ گواہی دی تھی
کہ یہ نسخہ قرآن کریم مکمل ہے اور بعینہ وہ ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور آپ نے امت کے
سپر د فر مایا اور یہ وہی قرآن کریم ہے جو بہت سے صحابہ نے مختلف حصوں کی صورت میں اپنے پاس محفوظ کر رکھا تھا اور
کم از کم چار صحابہ نے آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر نگرانی مکمل طور پرتحریری صورت میں محفوظ کر لیا تھا.حضرت عثمان
نے صحابہ کرام کے مشورہ اور اتفاق رائے کے مطابق مصحف ام کی لغت قریش پر اشاعت کی اور متفرق قرآنی تحریرات
کو جلانے کا حکم دیدیا جن میں لوگوں نے اپنے اپنے طور پر قرآن کریم یا اس کا کچھ حصہ تحریر کیا ہوا تھا.جہاں تک ابنِ وراق کے اس اعتراض کا تعلق ہے کہ عبد اللہ بن مسعود شسورۃ الفاتحہ اور معوذتین کو متن قرآن
کا حصہ تسلیم نہیں کرتے تھے.تو اس ضمن میں عرض ہے کہ واقعی بعض ایسی روایات ملتی ہیں کہ آپ اپنے صحائف
میں سے ان سورتوں کو مٹادیا کرتے تھے.لیکن ان روایات سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ پہلے درج کی تھیں لیکن پھر کسی
وجہ سے آپ کی رائے یہ ہوگئی کہ یہ سورتیں درج نہیں کرنی چاہئیں اس لیے مٹانا شروع کر دیا.
Page 288
الذكر المحفوظ
272
رادیات کے مطابق آپ شورۃ الفاتحہ کو ہر سورۃ سے متعلق سمجھتے تھے.آپ کا یہ موقف تھا کہ اگر سورۃ الفاتحہ
قرآن کریم میں درج کرنی ہوگی تو ہر سورۃ سے پہلے کرنی پڑے گی لیکن اس کے وحی الہی ہونے کے منکر ہر گز نہیں
تھے.بلکہ ہر نماز میں اس کی تلاوت کرتے تھے.جہاں تک ہر سورت سے قبل درج کرنے کا تعلق ہے تو اگر ہر
سورت سے قبل دو مرتبہ بھی درج کرنا کسی کی رائے ہو تو اس سے یہ کہاں ثابت ہوا کہ قرآن کریم میں کمی بیشی ہوگئی
یا حفاظت قرآن کا معاملہ ہی مشکوک ہو گیا؟ سورت تو محفوظ ہی ہے.یہ بات سو فیصد درست ہے کہ سورۃ الفاتحہ کا تعلق قرآن کریم کی ہر سورت سے ہے مگر اس سے یہ کیسے ثابت
ہو گیا کہ اسے نسخہ قرآن میں ہر سورۃ سے قبل درج کرنا بھی ضروری ہے یا پھر سرے سے درج
کرنا ہی نہیں چاہیئے ؟
جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا بلکہ کاتبین وحی کو یہ سورت قرآن کریم کے آغاز میں ایک ہی دفعہ
تحریر کروائی تو پھر ایسی رائے کی کیا اہمیت باقی رہ جاتی ہے.اس کے علاوہ قرآن کریم کی اندرونی گواہی بھی ملتی ہے اور واضح تاریخی ثبوت ملتے ہیں کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم
نے سورۃ الفاتحہ کو قرآن کریم کا حصہ قرار دیا اور قرآنی وحی میں شامل فرمایا.مثلاً حدیث ہے:
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِي
حُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ الْمُعَلَّى
قَالَ كُنْتُ أُصَلِّي فَدَعَانِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ أَجِبْهُ قُلْتُ يَا
رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ أَصَلِّي قَالَ أَلَمْ يَقُلْ اللَّهُ اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ
إِذَا دَعَاكُمْ ثُمَّ قَالَ أَلَا أُعَلِّمُكَ أَعْظَمَ سُورَةِ فِي الْقُرْآنِ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ
مِنْ الْمَسْجِدِ فَأَخَذَ بِيَدِي فَلَمَّا أَرَدْنَا أَنْ نَخْرُجَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ
قُلْتَ لَأُعَلِّمَنَّكَ أَعْظَمَ سُورَةِ مِنْ الْقُرْآنِ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
هِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُوتِيتُهُ
(بخاری کتاب فضائل القرآن باب فضائل فاتحة الكتاب)
حضرت ابی سعید بن معلی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نماز پڑھ رہا تھا تو آنحضور صلی اللہ علیہ
وسلم نے مجھے بلایا.میں جواب نہ دے پایا اور عرض کی اے اللہ کے رسول خاکسار نماز پڑھ رہا تھا اس
لیے جواب نہیں دے پایا.آپ نے فرمایا کہ کیا اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول
کی پکار کا جواب دو جب وہ تمہیں بلائیں؟ پھر آپ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا کہ میں مسجد سے
نکلنے سے پہلے تمہیں قرآن کریم کی سب سے عظیم الشان سورت کے بارہ میں بتاؤں گا.چنانچہ
Page 289
قرآن کریم میں تحریف کے الزامات کے جواب
273
جب آپ مسجد سے نکلنے لگے تو میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول ! آپ نے فرمایا تھا کہ آپ
مجھے قرآن کریم کی سب سے عظیم الشان صورت کے بارہ میں بتائیں گے.آپ نے فرمایا وہ سورت
أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ہے.یہ سبع المثانی اور القرآن العظیم ہے جو مجھے عطا کی گئی ہے.اسی طرح ایک روایت میں ہے:
حضرت انس فرماتے ہیں کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے.آپ نے ایک
شخص سے فرمایا' کیا میں تمہیں قرآن کریم کے سب سے افضل حصہ کے بارہ میں نہ بتاؤں؟“ پھر
آپ نے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت فرمائی.(مستدرك حاكم كتاب فضائل القرآن)
حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں:
ہم نے تجھے اے رسول سات آیتیں سورۃ فاتحہ کی عطا کی ہیں جو مجمل طور پر تمام مقاصد قرآنیہ
پر مشتمل ہیں اور ان کے مقابلہ پر قرآن عظیم بھی عطا فرمایا ہے جو مفصل طور پر مقاصد دینیہ کو ظاہر
کرتا ہے اور اسی جہت سے اس سورۃ کا نام ام الکتاب اور سورۃ الجامع ہے.ام الکتاب اس جہت
سے کہ جمیع مقاصد قرآنیہ اس سے مستخرج ہوتے ہیں اور سورۃ الجامع اس جہت سے کہ علوم قرآنیہ
کے جمیع انواع پر بصورت اجمالی مشتمل ہے.اسی جہت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی
فرمایا ہے کہ جس نے سورۃ فاتحہ کو پڑھا گو پا اس نے سارے قرآن کو پڑھ لیا.براہین احمدیہ روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 581, 580 حاشیہ نمبر 11)
اسی طرح فرماتے ہیں:
اور یا در ہے کہ ان دونوں فتنوں کا قرآن شریف میں مفصل بیان ہے اور سورۃ فاتحہ اور آخری
سورتوں میں اجمالاً ذکر ہے.مثلاً سورۃ فاتحہ میں دعا ولا الضالین میں صرف دو لفظ میں سمجھایا
گیا ہے کہ عیسائیت کے فتنہ سے بچنے کے لیے دعا مانگتے رہو جس سے سمجھا جاتا ہے کہ کوئی فتنہ
عظیم الشان در پیش ہے جس کے لیے یہ اہتمام کیا گیا ہے کہ نماز کے پنج وقت میں یہ دعا شامل کر
دی گئی اور یہاں تک تاکید کی گئی کہ اس کے بغیر نماز ہو نہیں سکتی جیسا کہ حدیث لا صلوة إِلَّا
بالْفَاتِحَةِ سے ظاہر ہوتا ہے.تحفہ گولڑو یہ روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 219-217)
پھر سورۃ الفاتحہ کا نام ہی اس کے قرآن کریم کی پہلی سورت ہونے کی ایک دلیل ہے.حضرت مسیح موعود نے
اس سورۃ کا نام الفاتحہ رکھے جانے کی ایک وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ اس سے قرآن کریم شروع ہوتا ہے.اس کا
ایک نام فاتحۃ الکتاب اور ایک نام ام القرآن اور ام الکتاب بھی ہے.جمع قرآن اور ترتیب کے قرآن کے موضوع میں ضمنی طور پر سورۃ الفاتحہ کے قرآن کریم کی ہی ایک، اور پہلی
Page 290
الذكر المحفوظ
274
سورت ہونے کے دلائل بیان ہو چکے ہیں.مثلاً یہ کہ یہ سورت قرآن کریم کے مضامین کا خلاصہ ہے اور یہ کہ اس سورۃ
کے الفاظ صرف اُن حروف پر مشتمل ہیں جو آئندہ سورتوں میں مقطعات کے طور پر استعمال ہوئے ہیں وغیرہ.یہاں
تمام دلائل کو دہرانا باعث طوالت ہوگا.یہ قابل ذکر ہے کہ یہ کہیں ذکر نہیں ملتا کہ حضرت عبداللہ نے کبھی امت کو یا
اپنے شاگردوں کو یہ کہا ہو کہ یہ سورتیں متن قرآن کا حصہ نہیں ہیں یا یہ کہ ان کو قرآن کریم میں درج نہیں کرنا چاہیے.معوذتین کے ضمن میں بھی حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے بارہ میں ایسی روایات ملتی ہیں جن سے یہ تاثر اُبھرتا
ہے کہ آپ کے نزدیک ان دو سورتوں کو قرآن کریم میں درج کرناضروری نہیں تھا.مثلاً روایت ملتی ہے:
حدثني محمد بن الحسين بن اشكاب حدثنا محمد بن ابي عبيدة بن
معن حدثنا ابى عن الاعمش عن ابى اسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد
قال كان عبد الله يحك المعوذتين من مصاحفه و يقول انهما ليستا من
كتاب الله تبارك و تعالى قال اعمش و حدثنا عاصم عن زر عن أبي بن
كعب قال سالنا عنهما رسول الله ﷺ قال فقيل لي فقلت
(مسند احمد بن حنبل کتاب مسند الانصار حدیث زر بن حبيش عن أبي بن كعب)
یعنی عبدالرحمن سے روایت ہے کہ عبداللہ بن مسعودؓا اپنے صحیفوں سے معوذتین مٹا دیا کرتے
تھے اور کہا کرتے تھے کہ یہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کا حصہ نہیں ہیں.اس روایت کے
ایک راوی اعمش یہ روایت بھی کرتے ہیں کہ عاصم نے اُبی بن کعب سے روایت کی ہے کہ ہم
نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے معوذتین کے بارہ میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ
مجھے ایسے ہی ارشاد ہوا اور میں بھی ایسے آگے کہ دیتا ہوں.اس روایت میں حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ایک ذاتی خیال درج کیا گیا ہے جس کے حق میں کوئی
دلیل نہیں دی گئی اور پھر یہ خیال اس مضمون کو بیان کرنے والی دوسرے رواۃ کی روایات میں بھی درج نہیں ہے.اس
سے ملتی جلتی روایات میں یہ تو آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے معوذتین اپنے صحیفہ سے خارج کر دی تھیں مگر یہ نہیں
لکھا کہ وہ انہیں کتاب اللہ کا حصہ نہیں مانتے تھے.اس روایت میں یہ بیان کرنے کے ساتھ کہ حضرت عبداللہ بن مسعود
کا یہ خیال تھا کہ کتاب اللہ کا حصہ ہی نہیں، اسی روایت کے ایک راوی اعمش نے ایک دوسرے راوی عاصم کے حوالہ
سے کاتب وحی حضرت ابی بن کعب سے روایت کر کے اس خیال کا قلع قمع کر دیا ہے کہ یہ خیال عبد اللہ بن مسعودرضی
اللہ عنہ یا عبد الرحمن کا تو ہوسکتا ہے لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے.حقیقت یہی ہے کہ بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے
نزدیک معوذتین بھی متنِ قرآن کریم کا حصہ ہیں.اس روایت کے مطابق حضرت ابی بن کعب نے آنحضور صلی اللہ
علیہ وسلم سے معوذتین کے وحی الہی ہونے کی تصدیق کروائی ہے.پس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح ارشاد
Page 291
قرآن کریم میں تحریف کے الزامات کے جواب
275
اور سنت کے مخالف کسی بھی ہستی کی رائے ہو تو اس کی حیثیت رڈی کے برابر بھی نہیں رہتی.پس اس روایت پر اس رائے کی بنیاد نہیں رکھی جاسکتی کہ حضرت عبد اللہ بن مسعود معوذتین کو وحی الہی نہیں
سمجھتے تھے کیونکہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے بارہ میں دوسرے رواۃ سے مروی روایات میں اس خیال کا کہیں
ذکر نہیں ملتا.نیز صرف ایک راوی عبد الرحمان بن یزید حضرت عبداللہ بن مسعود کی طرف یہ منسوب کرتے ہیں اور
ان کے بارہ میں میزان الاعتدال میں یہ لکھا ہے کہ آپ اہل کوفہ سے صحیح روایت نہیں کرتے.پس ایک تو راوی کی
یہ کمزوری اور پھر دوسری مستند اور تو اتر والی احادیث سے اختلاف کی بنیاد پر یہ مانا پڑتا ہے کہ راوی غلطی خوردہ ہے.حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے تو ہزاروں شاگرد تھے.اگر آپ کا فی الحقیقت یہ خیال ہوتا کہ معوذتین وحی الہی کا
حصہ نہیں ہیں تو اس کا کثرت سے ذکر ہونا چاہیے تھا.حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے اس طرز عمل کے بارہ میں کہ آپ معوذتین کو مصحف میں درج نہیں کرتے صحابہ
نے بھی نوٹ کیا اور حضرت ابی بن کعب سے جو کہ آنحضور کے کاتب وحی تھے، اس بارہ میں دریافت کیا گیا تو
آپ نے حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ کے اس طرز عمل کے بارہ میں اپنی رائے بیان کرتے ہوئے فرمایا.حدثنا سفيان بن عيينة عن عبدة و عاصم عن زر قال قلت لابی ان
اخاك يحكهما من المصحف فلم ينكر قيل لسفيان ابن مسعود قال
نعم و ليسا في مصحف ابن مسعود كان يرى رسول الله ﷺ يعوذ بهما
الحسن والحسين و لم يسمعه يقرؤهما في شيء من صلاته فظن انهما
عوزتان و اصر علی ظنه و تحقق الباقون كونهما من القرآن فاودعوهما اياه
(مسند احمد بن حنبل کتاب مسند الانصار هدیث زر بن حبيش عن أبي بن كعب)
یعنی ابن مسعود کا خیال تھا کہ رسول اللہ علہ حسن اور حسین رضی اللہ عنھما کو شیطان کے
مقابل پر اللہ کی پناہ میں دینے کے لیے یہ دعا دیا کرتے تھے.اس کے علاوہ انہوں نے آپ کو کبھی یہ
کسی نماز وغیرہ میں پڑھتے نہیں دیکھا اس لیے یہ خیال کر لیا کہ یہ صرف پناہ مانگنے والی دعائیں ہیں
اور اپنے اس خیال پر اصرار تھا جبکہ باقی صحابہ نے تحقیق سے ان کا قرآن کریم کا حصہ ہونا تسلیم کیا.ایک دوسری جگہ حضرت ابی بن کعب معوذتین کے قرآن کریم کا حصہ ہونے کی گواہی ان الفاظ میں دیتے ہیں.حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن عاصم و عبدة عن زر بن حبيش
قال سـالـت أبي بن كعب عن المعوذتين فقال سالت رسول الله ﷺ
فقال قيل لي فقلت فنحن نقل كما قال رسول الله ﷺ
(بخاری کتاب تفسیر القرآن باب قال المجاهد الفلق الصبح و غاسق...)
Page 292
الذكر المحفوظ
276
حضرت ابی بن کعب فر ماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے معوذتین
کے بارہ میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے ایسے ہی ارشاد ہوا اور اس لیے میں ایسے ہی تلاوت
کرتا ہوں.حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ پس ہم بھی اب ایسے ہی تلاوت کرتے ہیں
جیسے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرمایا کرتے تھے.اسی طرح یہ روایت بھی ملتی ہے:
عن زر قلت لأبي بن كعب ان ابن مسعود كان لا يكتب المعوذتين
في مصحفه فقال اشهد ان رسول الله ﷺ اخبرني ان جبريل عليه
السلام قال له قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ فقلتها فقال قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ فقلتها
فنحن نقل ما قال النبي ﷺ
(مسند احمد بن حنبل کتاب مسند الانصار حدیث زر بن حبيش عن أبي بن كعب)
زر بن حبیش کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابی بن کعب سے عرض کی کہ ابن مسعودؓ تو
معوذتین کو اپنے صحیفے میں درج نہیں کرتے.اس پر آپ نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے مجھے بتایا کہ جبریل علیہ السلام نے آپ کو پڑھا یا قُلْ أَعُوذُ
بِرَبِّ الْفَلَقِ میں نے ایسے ہی پڑھا.پھر پڑھایا قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ پس میں نے ایسے
ہی پڑھا.حضرت ابی بن کعب فر ماتے ہیں کہ پس ہم بھی اب ایسے ہیں تلاوت کرتے ہیں جیسے
کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرمایا کرتے تھے.امام احمد بن حنبل بہت سی دیگر اسناد سے بھی یہ روایت لائے ہیں جو اس روایت کے مستند ہونے کی ایک قوی دلیل ہے.بہر حال اگر کسی راوی کا یہ خیال تھا یا پھر یہ خیال حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ کا تھا تو بھی اسی کی کوئی وقعت نہیں
رہتی.ایک طرف متواتر تاریخی شہادتیں اور امت کی متفقہ گواہی تحریری تواتر ، حفاظ کا اجماع اور دوسری طرف
ایک راوی کا خیال یا اگر راوی کا خیال نہیں تو پھر حضرت عبد اللہ بن مسعود کا خیال.عقلِ سلیم کیا گواہی دیتی ہے کہ
کس کو درست تسلیم کیا جائے؟ راوی یا عبداللہ بن مسعودؓ کے خیال کو یا رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی گواہی اور
امت کی متفقہ شہادت اور تواتر کو؟ ظاہر ہے کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر آپ کے ساتھ ساری امت کی متفقہ
شہادت کے مقابل پر شخص واحد کو غلطی لگنازیادہ قرین قیاس ہے.علاوہ ازیں کتب احادیث میں اتنی کثرت سے ایسی احادیث ملتی ہیں جن میں معوذتین کے قرآن کریم کا
حصہ ہونے کا ذکر واضح الفاظ میں ملتا ہے.چنانچہ صحیح مسلم کی روایت ہے:
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جريف عن بيان عن قيس بن ابی حازم عن عقبة
Page 293
قرآن کریم میں تحریف کے الزامات کے جواب
277
بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم الم تر آيات أُنزلت الليلة
يُر مثلهن قط قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ -
(صحیح مسلم کتاب صلاة المسافرين و قصرها باب فضل قرائة المعوذتين)
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تجھے علم ہے کہ آج رات ایسی آیات نازل ہوئی ہیں کہ
ان جیسی پہلے کبھی نہیں دیکھی گئیں یعنی قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ.اس مضمون کی ایک حدیث سنن ترمذى فضائل القرآن عن رسول الله باب ما جاء في
المعوذتين میں اور ایک حدیث طبرانی نے حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ کی روایت سے بیان کی ہے (بحوالہ،
صدیق حسن خان صاحب : جمع تدوین قرآن مطبع معارف پریس اعظم گڑھ لکھنو : 1964 صفحہ 72) بخاری میں
بھی روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الاخلاص اور معوذتین
پڑھ کر سوتے تھے.(بخاری کتاب فضائل القرآن باب فضل المعوذتين)
الغرض صحاح ستہ کی سب کتب میں معوذتین کے قرآن کریم کا حصہ ہونے کے بارہ میں احادیث ملتی ہیں.یہی قرین قیاس ہے کہ حضرت عبد اللہ بن مسعود ا نہیں قرآنی وحی ہی سمجھتے تھے اور محض ان معنوں میں دعا قرار دیتے
تھے جو معانی حضرت مسیح موعود علیہ السلام ان الفاظ میں بیان فرمارہے ہیں.سورۃ فاتحہ میں تین دعائیں سکھلائی گئی ہیں.(۱) ایک یہ دعا کہ خدا تعالیٰ اس جماعت میں
داخل رکھے جو صحابہ کی جماعت ہے اور پھر اس کے بعد اس جماعت میں داخل رکھے جو مسیح موعود
کی جماعت ہے جن کی نسبت قرآن شریف فرماتا ہے وَآخَرِينُ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمُ
( الجمعة : 4) غرض اسلام میں یہی دو جماعتیں منعم علیہم کی جماعتیں ہیں اور انہی کی طرف اشارہ
ہے صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمُ میں کیونکہ تمام قرآن پڑھ کر دیکھو جماعتیں دوہی ہیں.ایک صحابہ رضی اللہ عنہم کی جماعت.دوسری و آخَرِینَ مِنْهُمْ کی جماعت جو صحابہ کے رنگ میں
ہے اور وہ مسیح موعود کی جماعت ہے.پس جب تم نماز میں یا خارج نماز کے یہ دعا پڑھو کہ اِهْدِنَا
الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ تو دل میں یہی ملحوظ رکھو کہ میں صحابہ
اور مسیح موعود کی جماعت کی راہ طلب کرتا ہوں.یہ تو سورۃ فاتحہ کی پہلی دعا ہے.(۲) دوسری دعا
غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمُ ہے جس سے مراد وہ لوگ ہیں جو مسیح موعود کو دکھ دیں گے اور اس دعا
کے مقابل پر قرآن شریف کے اخیر میں سورۃ تبتُ يَدَا أَبِي لَهَبٍ ہے.(۳) تیسری دعاوَلَا
الضَّالِّينَ ہے اور اس کے مقابل پر قرآن شریف کے اخیر میں سورۃ اخلاص ہے یعنی قُلْ هُوَ
Page 294
الذكر المحفوظ
278
اللهُ اَحَدٌ اللهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدُ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا اَحَدٌ اور اس کے بعد دو اور
سورتیں جو ہیں یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس یہ دونوں سورتیں سورۃ تنبت اور سورۃ اخلاص کے
لیے بطور شرح کے ہیں اور ان دونوں سورتوں میں اس تاریک زمانہ سے خدا کی پناہ مانگی گئی ہے
جب کہ لوگ خدا کے میسی کو دکھ دیں گے اور جب کہ عیسائیت کی ضلالت تمام دنیا میں پھیلے گی.(تحفہ گولڑوی روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 219-217)
پس جہاں تک ابن مسعود کا معوذتین کو قرآنی وحی سمجھنے یانہ سمجھنے کا تعلق ہے تو اغلباً آپ معوذتین کو قرآن کریم
کے متن کا حصہ اور وحی الہی سمجھتے تھے اور اگر ایسا نہیں ہے تب بھی یہ امر تو واضح ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
اور باقی تمام صحابہ ان دونوں سورتوں کو متن قرآن اور وحی سمجھتے تھے.یہ بات واضح ہے کہ جب امت کی متفقہ
گواہی موجود تھی کہ جو قرآن ابو بکر نے جمع کروایا ہے وہ بعینہ وہی ہے جو امت نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
سے سُنا ،لکھا، حفظ کیا اور سیکھا ہے اور ان گواہوں میں حضرت عبد اللہ کے شاگر دبھی شامل تھے.اس صورت میں
ایک شخص کا اختلاف کیا حیثیت رکھتا ہے؟
نیز یہ امر بھی پیش نظر رہنا چاہیے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ صحابہ میں ممتاز اور عالم قرآن تھے.کوفہ
میں با قاعدہ درسِ قرآن کی ایک یونیورسٹی آپ نے قائم کی ہوئی تھی.ہزاروں ہزار آپ کے شاگرد تھے مگر ان شاگردوں
میں سے کوئی بھی ایسی روایت نہیں کرتا کہ آپ معوذتین کو متن قرآن کا حصہ نہیں سمجھتے تھے.بلکہ شاگردوں کی جو
روایتیں ملتی ہیں ان کے مطابق آپ قرآن کا درس مع معوذتین دیا کرتے تھے.(بحوالہ ، صدیق حسن خان صاحب:
جمع تدوین قرآن مطبع معارف پریس اعظم گڑھ لکھنو : 1964 صفحہ 72) اگر بالفرض ابن مسعودؓ نے ان دوسورتوں
کا متن قرآن کا حصہ ہونے کا انکار کیا ہی تھا تو کثرت سے اس
کا ذکر ہونا چاہیے تھا.حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب خلیفہ اسیح الثانی اصلح الموعود رضی اللہ عنہ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ
کے اس نظریہ کے بارہ میں فرماتے ہیں:
اس کی بنیاد کسی دلیل پر نہیں.واقعات کے متعلق دلیل صرف وہی شہادت ہو سکتی ہے جو یا تو
نظری ہو یا سماعی یعنی یا تو اس کی شہادت جس نے خود واقعہ دیکھا ہے یا پھر اگر کسی اور کی طرف
منسوب کرے تو اس کے الفاظ بیان کرے.لیکن حضرت عبد اللہ بن مسعود کا یہ بیان نہیں کہ
انہوں نے نبی کرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے اس طرح سُنا بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ان دونوں سورتوں
کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ ان کے
ساتھ استعاذہ کیا کریں اور چونکہ یہ دونوں سورتیں استعاذہ ہیں.اسلئے معلوم ہوا کہ قرآن ختم
Page 295
قرآن کریم میں تحریف کے الزامات کے جواب
279
ہو گیا.ظاہر ہے کہ یہ محض ان کا قیاس ہے.اس کے مقابل دوسرے مقتدر صحابہ کا بیان ہے کہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورتیں انہیں قرآن کے حصہ کے طور پر لکھوائیں.اس لیے
حضرت عبداللہ بن مسعود کا قیاس در آنحالیکہ وہ خود بھی تسلیم کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کے زمانہ میں یہ قرآن کے ساتھ لکھی اور پڑھی جاتی تھیں کوئی وقعت نہیں رکھتا.پس یہ سورتیں
یقیناً قرآن کریم کا حصہ ہیں اور قرآن کریم کے خاتمہ کے لیے خدا تعالیٰ نے ان کو چنا ہے.( تفسیر کبیر جلد دہم صفحہ 544 کالم اول زیر تفسیر الفلق)
خلاصہ کلام یہ کہ معوذتین کے مسئلہ میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے بارہ میں یہ رائے قائم کرنا کہ وہ انہیں
وحی الہی کا حصہ نہیں سمجھتے تھے درست نہیں کیونکہ اول تو صرف ایک راوی یہ خیال ظاہر کرتے ہیں اور راوی بھی وہ
جن کا اہل کوفہ سے درست روایت کرنا مشکوک ہے.علاوہ ازیں دیگر متواتر روایات میں یہ بات عبداللہ بن
مسعود کی طرف منسوب نہیں کی گئی اور اگر حضرت
عبد اللہ واقعی انہیں وہی قرآن کا حصہ نہیں مانتے تھے تو آپ اپنے
خیال کے حق میں کوئی دلیل نہیں دیتے.یہ بھی مد نظر رہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے بارہ میں روایات میں جو یہ درج ہے کہ وہ اپنے صحائف سے معوذتین
مٹادیا کرتے تھے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اولاً آپ ان سورتوں کو اپنے صحیفہ میں درج کیا کرتے تھے.پھر آپ کی رائے
بدل گئی اور باقی امت سے مختلف ہو گئی لیکن اس کے حق میں کوئی دلیل نہیں دی اس لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہو سکتی.اس اختلاف کی اس لیے بھی اہمیت نہیں کیوں کہ اول کا تبین وحی گواہی موجود ہے کہ معوذتین متن قرآن کا حصہ
ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متن قرآن کریم میں درج کروائی تھیں.دوم یہ کہ ساری امت کی گواہی جس
صحیفہ قرآن پر اکٹھی کی گئی تھی اس میں معوذتین درج کی گئی ہیں اور دوسری طرف صرف آپ اختلاف کر رہے تھے
جس کی کوئی دلیل نہیں ملتی.اگر در حقیقت کوئی شک ہوتا تو لازماً امت مسلمہ میں سے عبداللہ کا ساتھ دینے والے
صحابہ اور دیگر ہزاروں افراد کھڑے ہو جاتے یا کم از کم آپ کے شاگردوں میں سے کچھ آپ کی حمایت کرتے.آپ
قرآن کریم کی درس و تدریس میں مشغول رہتے تھے مگر اس کے باوجود آپ کے اس خیال کے حق میں کوئی شہادت
نہیں ملتی.یہاں تک کہ آپ کے شاگردوں میں سے کوئی بھی اس خیال کی حمایت نہیں کرتا نظر نہیں آتا.پس ثابت شدہ اور متفقہ حقائق کو چھوڑ کر ایک بے دلیل رائے کو وہی شخص اہمیت دے سکتا ہے جس کا مقصد حق
کی جستجو نہیں بلکہ اعتراض برائے اعتراض ہے.بہر حال یہ اختلافات اس وقت بالکل ہی بے حیثیت ہو جاتے ہیں جب یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ حضرت
عبد اللہ بن مسعود بالآخر عہد صدیقی میں ہی اس اختلاف کو ختم کر کے اجماع امت سے تیار کیے جانے والے صحیفہ
Page 296
الذكر المحفوظ
280
سے بکلی متفق ہو گئے اور پھر تیسری بار مصحف ام کے مطابق قرآن کریم لکھا جس میں سورۃ الفاتحہ اور معوذتین
درج تھیں.مگر اس بار آپ کا حضرت ابوبکر کے جمع کردہ صحیفہ سے اتنا فرق ضرور تھا کہ یہ صحیفہ آپ نے اپنی پسند کی
قراءت پر لکھا تھا.(عبدالصمد صارم الازھری : تاریخ القرآن، ایڈیشن 1985 ندیم یونس پرنٹرز لا ہور، پبلشرز :
مکتبہ معین الادب اردو بازار لاہور صفحہ 81)
حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ کے مقام اور مرتبہ اور خدمت قرآن کے ضمن میں آپ کی کوششوں کو مد نظر رکھنے
سے دل میں پیدا ہونے والی محبت ہمیں مجبور کرتی ہے کہ حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ کے بارہ میں جو بھی اچھا امکان
ہوسکتا ہے وہی سوچا جائے.آپ دن رات قرآن کریم کی درس و تدریس میں مشغول رہتے تھے اور باقاعدہ ایک
نظام کے تحت اپنے تلامذہ کوسند سے بھی نوازتے تھے.گویا ایک مدرس یا پروفیسر کی طرح آپ تعلیم القرآن کے
فریضہ سے وابستہ رہے.آپ کے اخلاص اور ایمان کا اظہار اس واقعہ سے ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
حیات مبارکہ میں ایک مرتبہ آپ گلی سے گزر رہے تھے کہ آپ کے کانوں میں آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پڑی
کہ بیٹھ جاؤ.آپ و ہیں گلی میں بیٹھ گئے اور بچے کی طرح زمین پر بیٹھے بیٹھے گھسٹ گھسٹ کر مسجد کی طرف بڑھنے لگے.کسی نے آپ سے اس طرح گھسٹ کر آگے بڑھنے کا سبب پوچھا تو فرمانے لگے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا
حکم سنا ہے کہ بیٹھ جاؤ تو میں بیٹھ گیا.اس نے کہا کہ یہ حکم آپ کے لیے تو نہیں تھا تو آپ نے فرمایا کہ اگر اسی
حالت میں میری جان نکل جاتی تو ؟ میں اپنے مولیٰ کے حضور اس حالت میں حاضر نہیں ہونا چاہتا تھا کہ میں نے
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم سنا اور اطاعت نہیں کی.پس کیسے ممکن ہے کہ اس بلند مرتبہ ایمان کا صحابی
قرآن کریم کے معاملہ میں دانستہ کوئی غلط بات سوچ بھی سکے؟
آج غبی اور شقی القلب معترض زبان طعن تو دراز کرتا ہے لیکن اس بات کو بالکل نظر انداز کر دیتا ہے کہ حضرت
عبد اللہ بن مسعودؓ نے اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے یہ اختلافات ختم کر لیے اور باقی امت کے ساتھ متفق ہو گئے.بصورت دیگر ہرگز مصحف ام کے مطابق اپنا نسخہ قرآن نہ تحریر کرتے اور اپنے اختلاف پر قائم رہتے.صحابہ رسول
تو حفاظت قرآن کریم کے لیے کٹ مرنے کو تیار رہتے تھے اور اس معاملہ میں ان کے لیے کسی قسم کا کوئی سمجھوتہ کرنا
اممکن تھا.چنانچہ ساری اسلامی تاریخ اس قسم کی مثالوں سے بھری پڑی ہے.ان تمام تاریخی حقائق پر مجموعی نظر
ڈالنے سے یہ امر واضح ہو جاتا ہے کہ حفاظت قرآن کے معاملہ میں تو کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں کیا جاسکتا.حضرت
عبداللہ بن مسعودؓ کے معاملہ میں اگر روایات میں مکمل تفصیلات بیان ہیں اور کچھ بھی کمی نہیں ہے تو بھی زیادہ سے
زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ عدم علم کی وجہ سے اور قرآن کی محبت اور غیرت میں نیز حفاظت قرآن کے لیے ایک ایسے
حکم کا انکار کر بیٹھے جو سراسر بھلائی کا تھا.اس کا قرآن کریم کی حفاظت پر کیا اثر پڑا؟ ہاں یہ صحابہ کے بیمثال عشق
Page 297
قرآن کریم میں تحریف کے الزامات کے جواب
281
قرآن اور حفاظت قرآن کے معاملہ میں بے پناہ غیرت پر دلیل ہے.پس حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے اگر اختلاف
کیا تو غیرت ایمانی کے جذبہ سے کیا اور اگر سر تسلیم خم کیا تو عشق قرآن اور اطاعت خلافت کے جذبہ سے.اسی طرح صحیفہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو اختلاف مصاحف کے ضمن میں بہت بڑھا کر پیش کیا جاتا ہے.ابن وراق کو بھی اعتراض ہے کہ حضرت ابی بن کعب نے صحیفہ میں سورۃ الفیل اور سورۃ القریش کے درمیان بسم
اللہ نہیں لکھی تھی.مگر آج قرآن کریم کے شائع کیے جانے والے نسخوں میں باقی سورتوں کی طرح ان دونوں
سورتوں کے درمیان
بھی بسم اللہ لکھی جاتی ہے.حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے کتابت وحی کے وقت غلطی ہوگئی تھی اور بسم اللہ تحریر ہونے سے رہ گئی مگر
باقی کاتبین اور حفاظ صحابہ کا اتفاق تھا سورۃ الفیل اور سورۃ القریش کے درمیان بسم اللہ ہے کیونکہ یہ دونوں الگ
الگ سورتیں ہیں.اور حضرت ابی بن کعب نے بھی اصرار نہیں کیا کہ ان دونوں سورتوں کے درمیان بسم اللہ نہیں
للھنی چاہیے بلکہ اس معاملہ میں بالکل خاموش ہیں.گویا خاموش رہ کر اپنی غلطی کا اقرار کر رہے ہیں.پس اس
اعتراض کا جواب تو یہ سوال ہی ہے کہ شخص واحد سے غلطی سرزد ہونا زیادہ قرین قیاس ہے یا کل امت سے؟ جو کام
رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے زیر نگرانی ہوا اور تمام امت نے مجموعی طور پر اس صحیفہ کے استناد پر گواہی دی تو
اس کے بعد کسی ایک شخص کی غلطی کی کیا اہمیت ہے؟ کیا آپ کو اصرار تھا کہ آپ درست ہیں اور باقی صحابہ غلطی پر
ہیں؟ ہرگز نہیں !! مستشرقین کا معاملہ تو مدعی ست گواہ چست والا ہے.پس یہ اعتراض تو بالکل ہی بے حیثیت ہے.علاوہ ازیں لوگ عام طور ایک غلطی کا شکار ہو جاتے ہیں اور مستشرقین بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ
گویا اُس دور میں بھی قرآن کریم کے ورژن (Version) ہوا کرتے تھے.اُس دور کو آج کے حالات پر قیاس
کر لیا جاتا ہے حالانکہ اُس دور میں کوئی نسخہ پریس میں تو نہیں چھپتا تھا کہ یہ کہ دیا جائے کہ یہ قرآن کریم کا فلاں
ورژن ہے اور یہ فلاں.جو نسخہ حضرت ابی بن کعب سے منسوب تھاوہ صرف ایک نسخہ تھا.اس میں اگر کوئی غلطی راہ
پاگئی تھی تو صرف ایک نسخہ میں یہ غلطی تھی.اس سے یہ مراد تو نہیں کہ حضرت ابی بن کعب کے نسخہ سے کی جانے والی
نقول میں ہمیشہ اہتمام کیا جاتا کہ سورۃ الفیل اور سورۃ القریش کے درمیان بسم اللہ لکھی ہی نہ جائے.پھر جب
قرآن کریم کو حضرت ابوبکر کے عہد خلافت میں جمع کیا گیا تو کیا اس وقت حضرت ابی نے کوئی اعتراض کیا ؟ نہیں !!
بلکہ آپ بھی امت کے ساتھ شامل تھے اور مصحف ام کے استناد پر باقی امت سے متفق تھے.جب آپ کو کوئی
اعتراض نہیں تو ابن وراق
کو کیا تکلیف ہے؟ اس اعتراض کے جواب میں حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب
خلیفہ امسیح الثانی المصلح الموعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:
أبي بن کعب ، اس میں کوئی شبہ نہیں، کہ اُن چار آدمیوں میں سے تھے جن کے متعلق
Page 298
الذكر المحفوظ
282
رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ قراءامت ہیں اگر کسی شخص نے قرآن سیکھنا ہو تو ان
سے سیکھے.لیکن جہاں یہ درست ہے وہاں اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا کہ ابی ابن کعب
ویسے ہی غلطی کر سکتے ہیں جیسے کوئی اور شخص غلطی کر سکتا ہے.ہم اپنے پاس سے ایک مضمون بنا کر
وو
لکھتے ہیں لیکن اُس میں بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں.کہیں ” ہے رہ جاتا ہے، کہیں ” کا“ کی جگہ
کی لکھا ہوا ہوتا ہے، کہیں کوئی اور غلطی ہو جاتی ہے.کا تب قرآن کریم لکھتے ہیں تو با وجوداس
کے کہ بعض بڑے بڑے مشتاق کا تب ہوتے ہیں پھر بھی اُن سے کئی غلطیاں ہو جاتی ہیں.اسی
طرح ممکن ہے کسی جگہ پر غلطی سے ابی ابن کعب کو خیال نہ رہا ہو اور وہ ان دونوں سورتوں کے
درمیان بسم اللہ لکھنا بھول گئے ہوں.جبکہ قرآن کریم کا جو نسخہ ہمارے پاس ہے اُس میں ان
دونوں سورتوں کو الگ الگ لکھا ہوا ہے اور اُن کے درمیان بسم اللہ بھی لکھا ہوا ہے اور قرآن کریم
کا یہ نسخہ ایسا ہے جس کی ترتیب میں صرف ابی ابن کعب نے ہی کام نہیں کیا بلکہ بہت سے اور
صحابہ نے بھی جن کا رتبہ قراءت میں حضرت ابی ابن کعب سے کم نہ تھا کام کیا تھا.چاروں قراء
نے مل کر اس میں حصہ لیا ہے اور باقی سارے صحابہؓ نے بھی مل کر حصہ لیا ہے.جو نسخہ ان ساروں
نے مل کر لکھا ہے یہ صاف بات ہے کہ وہ زیادہ احتیاط سے لکھا ہوا ہو گا.پھر ابی ابن کعب
کے نسخہ میں تو غلطی کا امکان ہے کیونکہ کسی نے اُس پر بحث نہیں کی لیکن اس پر بخشیں کی گئی
ہیں اور صحابہؓ نے اس کے متعلق اپنی شہادتیں اور گواہیاں دی ہیں.کوئی سورۃ نہیں لکھی گئی ، کوئی
آیت نہیں لکھی گئی ، کوئی زیر اور زبر نہیں لکھی گئی جس کے متعلق دو قسم کی شہادتیں نہیں لی گئیں.ایک یہ کہ تحریر موجود ہو.دوسرے یہ کہ زبانی گواہ موجود ہوں جو یہ کہتے ہوں کہ انہوں نے
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا سنا ہے.یہ کتنی بڑی محنت ہے اور کتنی بڑی احتیاط کا ثبوت
ہے.زبانی گواہی کو نہیں مانا گیا جب تک اُس کے ساتھ تحریری شہادت نہ ہوا اور تحریری شہادت کو
نہیں مانا گیا جب تک اُس کے ساتھ زبانی گواہ نہ ہوں.گویا تحریر بھی موجود ہو اور زبانی گواہ بھی
موجود ہوں تب کسی سورۃ یا آیت کو قرآن کریم میں شامل کیا جاتا اور یہ زبانی گواہ بھی بعض دفعہ
سینکڑوں تک ہوا کرتے تھے صرف ایک دو آیتیں ایسی ہیں جن کے متعلق صرف دو دو گواہ ایسے
ملے ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے ایسا نا ہے.لیکن
باقی ساری آیتیں اور سورتیں ایسی ہیں جن میں کسی کے ہیں کسی کے پچاس اور کسی کے سوگواہ
تھے اور بہت سے حصوں کے ہزاروں گواہ موجود تھے.بہر حال وہ شہادت جو رسول کریم صلی اللہ
Page 299
قرآن کریم میں تحریف کے الزامات کے جواب
283
علیہ وسلم کی تحریر سے ثابت ہوتی تھی خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے املاء اور لکھوانے ثابت
ہوتی تھی.پھر زبانی گواہ آتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم نے رسول کریم سے ایسا سنا یا ہم نے رسول
کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے ایسا پڑھا ہے، وہی قطعی اور یقینی کبھی جاتی تھی اور اسی قسم کی
شہادتوں کے بعد ہی قرآن کریم میں کوئی آیت شامل کی جاتی تھی پس وہ نسخہ قرآن جو ہمارے
پاس ہے اور جس میں سورۃ الفیل اور سورۃ القریش کو الگ الگ لکھا ہوا ہے.یہ خود اپنی ذات میں
اس بات
کا یقینی ثبوت ہے کہ یہ دونوں سورتیں الگ الگ ہیں.اگر ایک شخص اپنے طور پر قرآن کریم
لکھتا ہے تو ہوسکتا ہے کہ دوسورتوں کے درمیان بسم اللہ اُس سے غلطی سے رہ جائے.پس یہ کوئی
دلیل نہیں جو پیش کی گئی ہے.دوسرا جواب یہ ہے کہ اس منفی دلیل کے علاوہ ایسی مثبت دلیل بھی موجود ہے کہ سورۃ قریش
سے پہلے بسم اللہ کبھی ہوئی تھی اور اس وجہ سے اس کے الگ سورۃ ہونے میں کوئی شبہ نہیں اور وہ
یہ ہے کہ تمام مؤرخین اور تمام قراء اور تمام ماہرین فن صحابہ سے متفقہ طور پر یہ بات ثابت ہے کہ
صرف ایک سورۃ البراءة ایسی ہے جس سے پہلے بسم اللہ نہیں لکھی گئی اور اس شہادت کے دینے
والوں میں خود اُبی بن کعب بھی شامل ہیں.اور کوئی سورۃ نہیں جس سے پہلے بسم اللہ نہ ہو تو
اگر ابی ابن کعب نے اپنے نسخہ قرآن میں سورۃ قریش سے پہلے بسم اللہ نہیں لکھی تو یہ بات خود
تواتر کے خلاف ہے اور تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ اُن سے غلطی ہوئی.( تفسیر کبیر جلد 10 صفحہ 85،84 تفسیر القریش:2)
اسی طرح ایک یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اُبی بن کعب کے صحیفہ میں دوسورتیں درج تھیں جو آج شائع ہونے
والے قرآن کریم کے نسخوں میں درج نہیں کی جاتیں.ان میں ایک تو وہ دُعا ہے جو دعائے قنوت کے نام سے
امت میں معروف ہے.دوسری دراصل ایک دعائے ختم القرآن ہے.یہ صرف ایک وسوسہ ہے کہ جس کا حقیقت سے کوئی بھی تعلق نہیں.نہ حضرت
ابی کا اور نہ کسی اور صحابی کا یہ دعویٰ
ملتا ہے کہ یہ دوسورتیں ہیں اور متن قرآن کا حصہ ہیں.حضرت
ابوبکرؓ کے عہد خلافت میں مصحف ام کی تیاری کے وقت
ان دو سورتوں کا کوئی جھگڑا پیدا نہیں ہوا.حضرت عثمان کے دور میں ہونے والی تدوین میں حضرت ابی ابن کعب
بھی شامل تھے.لیکن کوئی روایت نہیں ملتی کہ آپ نے کہیں ایسا کہا ہو کہ یہ دوسورتیں ضرور شامل کی جائیں.اسی طرح
اُس دور میں کوئی صحابی ایسا نہیں ملتا کہ جو یہ اصرار کرتا ہو کہ ابی کے صحیفہ میں دوسورتیں زائد ہیں جو مصحف الامام
میں درج نہیں کی گئیں.اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نہ تو حضرت ابی کا یہ دعوی تھا کہ یہ سورتیں متن قرآن کا حصہ
Page 300
الذكر المحفوظ
284
ہیں اور نہ ہی دیگر صحابہ ان کو متن قرآن کا حصہ سمجھتے تھے.یہ صرف دعا ئیں تھیں جو آنحضور نے سکھائیں تھیں.ور نہ ضرور ان سورتوں کو بھی قرآن کریم میں درج کیا جاتا.اختلاف مصاحف کے ضمن میں ان اتحاد کا فرقوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی بڑا اختلاف نہیں تھا.ایک صحابی
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی رائے مختلف تھی مگر انہوں نے بعد میں اپنی غلطی تسلیم کر لی.دوسرا اختلاف
دراصل اختلاف تھا ہی نہیں بلکہ تحریر کی ایک غلطی تھی جس پر کاتب وحی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے اصرار
کرنا تو درکنار یہ بھی نہیں کہا کہ یہ میری رائے ہے بلکہ خاموش رہ کر اپنی غلطی تسلیم کر لی.اسی طرح دوسری دو
دعاؤں کے بارہ میں بھی نہ آپ نے اور نہ کسی اور صحابی نے کبھی یہ دعوی کیا کہ یہ بھی متن قرآن کا حصہ ہیں بلکہ
حضرت ابی نے تاحیات امت کے متفقہ طرز عمل کے مطابق اپنا نمونہ قائم کیا.پھر ان دونوں اصحاب کے اختلاف کی کیا اہمیت ہو سکتی جبکہ یہ دونوں اصحاب آپس میں بھی متفق نہ تھے.نہ
حضرت ابی حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ سے متفق تھے کہ معوذتین اور سورۃ الفاتحہ نسخہ قرآن میں درج نہیں کرنی چاہئیں
اور نہ حضرت عبداللہ بن مسعود یہ کہتے تھے کہ حضرت ابی کے نسخہ میں درج دود عا ئیں متن قرآن کا حصہ ہیں.سورہ فیل
اور سورہ قریش کے درمیان بسم اللہ نہ لکھنے پر تو کسی صحابی کو اصرار نہیں تھا، حضرت ابی بن کعب کو بھی نہیں.یہ اختلاف تو اس وقت بالکل ہی بے حیثیت ہو جاتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر نے صحابہ
کی گواہی لی تھی کہ جو قرآن کریم ان کی نگرانی میں ضبط تحریر میں لایا جارہا ہے وہ وہی ہے جو رسول کریم سے امت نے سیکھا
ہے، اس وقت یہ تمام تر مصاحف موجود تھے.بالخصوص جب ہم دیکھتے ہیں کہ اعلان یہ کیا جارہا تھا کہ وہ صحابہ جنہوں
نے رسول کریم سے قرآن کریم حفظ کیا ہو یا جن کے پاس ایسی تحریرات وجی موجود ہوں جو رسول کریم کے زیر نگرانی یا
آپ کے حضور پیش کر کے
مستند بنائی گئی ہوں تو دو گواہوں کے ساتھ حاضر ہوں.پس یہ بہت عظیم الشان گواہی تھی کہ وہ
سب صحابہ جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے رو برو قرآن کریم لکھایا آپ سے حفظ کیا، یا اپنے حفظ اور تحریر کو
رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے حضور پیش کر کے اس کی تصدیق کر والی تھی وہ آج پورے اطمینان سے یہ گواہی دے
رہے تھے کہ یہ قرآن کریم وہی ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے امت کو دیا ہے.پس اس وقت حضرت ابی
کا یہ دوسورتیں مصحف ام میں درج نہ کروانا اور صحابہ میں سے کسی کا ان دو سورتوں کو پیش نہ کرنا بتا تا ہے کہ یہ سورتیں تھیں
ہی نہیں.حضرت عبد اللہ کا اختلاف اور حضرت
ابی کا صحیفہ اسی صورت میں قابل توجہ ہوتا اگر کچھ صحابہ اُن کے حق میں
ہوتے اور جس طرح مصحف ام پر صحابہ کا اجماع تھا ان تبدیلیوں کے حق میں کم از کم کچھ صحابہ تو گواہی دیتے.مگر پورے
اطمینان اور خاموشی سے متفق ہو جانا یہ بتاتا ہے کہ صحابہ کو مصحف ام سے کوئی اختلاف نہیں تھا.
Page 301
قرآن کریم میں تحریف کے الزامات کے جواب
285
اختلاف قراءت
حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری سالوں میں کثرت سے حلقہ بگوش اسلام ہونے
والوں کی آسانی اور قرآن کریم کی کثرت اشاعت کی غرض سے خدا تعالیٰ کی اجازت سے ایک سے زائد قراء توں پر
قرآن کریم کی اشاعت کی تھی.حضرت عثمان نے اپنے عہد خلافت میں عالم اسلام
کو دوبارہ ایک قراءت پر جمع کر دیا.مستشرقین کی طرف سے بہت شد و مد کے ساتھ ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ حضرت عثمان کے
عہد خلافت میں قرآن کریم کے مختلف ورژن رائج تھے اور بہت اختلاف ہو گیا تھا.پھر حضرت عثمان نے ایک
متن تیار کروا کر بطور مرکزی متن شائع کر دیا اور باقی سب جلوا دیے.مستشرقین کے اس دجل کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ قراءت دراصل چیز کیا ہے.عام طور پر تر تیل اورلحن کے ساتھ تلاوت کرنے کو قراءت سمجھا جاتا ہے.مگر جو مسئلہ اختلاف قراءت کے عنوان
سے زیر بحث ہے اس سے صرف لحن یا لہجہ کا فرق مراد نہیں بلکہ ایک دوسرا فرق بھی مراد ہے جسے آنحضور صلی اللہ
علیہ وسلم نے حرف کے لفظ سے بیان فرمایا ہے.آپ نے فرمایا اُنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ فَاقْرَوُا
مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ.(بخارى كتاب فضائل القرآن باب انزل القرآن على سبعة حرف) یعنی قرآن کریم سات حروف
میں نازل ہوا ہے پس جیسے آسانی ہو، پڑھ لیا کرو.قراءت کے فرق سے یہ دھو کہ نہیں کھانا چاہیے کہ قرآنی آیات مختلف ہیں.اس حقیقت کو بہتر طور پر صرف
عربی دان ہی سمجھ سکتا ہے کیونکہ یہ خصوصیت اپنی کامل شکل میں صرف عربی زبان میں ہی ہے اور کسی دوسری زبان
میں نہیں پائی جاتی.عربی زبان کے الفاظ کے زیر اور ز بر کئی طرح جائز ہوتے ہیں لیکن معنی نہیں بدلتے کسی حرف
کے نیچے زیر لگا لیں تب بھی جائز ہوتا ہے اور اگر اُس پر زبر پڑھیں تب بھی جائز ہوتا ہے اور معنی ایک ہی رہتے
ہیں.کبھی تو یہ عام قاعدہ کے طور پر فرق ہوتا ہے یعنی علمی زبان میں اس لفظ کو کئی طرح بولنا جائز ہوتا ہے اور بعض
موقعوں میں یہ فرق قبائل کے لحاظ سے بھی ہوتا ہے یعنی بعض قبائل یا بعض خاندان ایک لفظ کو زیر ) کے
ساتھ پڑھتے ہیں.بعض لوگوں کے مُنہ پر زبر (-) چڑھی ہوئی ہوتی ہے.اسی طرح بعض دفعہ یہ فرق بعض
حروف کی ادائیگی میں ہوتا ہے.ایک علاقہ کے لوگ ایک حرف نہیں بول سکتے اور اس کی جگہ دوسرا حرف بولتے
ہیں اور کبھی یہ فرق الفاظ میں بھی ہوتا ہے.ایک قبیلہ ایک لفظ کو ایک معنی میں استعمال کرتا تھا جبکہ دوسرا قبیلہ اُسی
لفظ کا استعمال دوسرے معنی میں کرتا تھا.گویا ایک قبیلہ ایک لفظ سے کچھ اور مراد لیتا تھا اور دوسرا قبیلہ اُسی لفظ کے
کچھ اور معنی کرتا تھا.رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم قرآن کریم کی معنوی حفاظت اور کثرت اشاعت کی غرض
Page 302
الذكر المحفوظ
286
سے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے مختلف قبائل کو اپنے قبیلہ کی زبان اور لغت کے مطابق پڑھنے کی اجازت دیدیتے
تھے.قراءتوں کے حوالہ سے ابن وراق نے بھی اعتراض کیا ہے.کہتا ہے :
We need to retrace the history of the Koran text to
understand the problem of variant versions and variant
readings,...(Ibn Warraq: Why I am Not A Muslim, Prometheus Books, New
York, 1995, under heading; The Koran: Pg (108)
یعنی ہمیں مختلف versions اور مختلف قراءتوں کے مسائل کو سمجھنے کے لیے قرآن کریم کی
تاریخ کو دوبارہ کھنگالنے کی ضرورت ہے.پھر کہتا ہے:
The seven [versions] refer to actual differences in the
written and oral text., to distinct versions of Quranic
verses, whose differences, though they may not be great,
are nonetheless real and substantial.(op.cit.110)
یعنی سات قراء توں کا مسئلہ قرآن کی تحریر اور تلاوت میں ایک حقیقی اختلاف کی نشان دہی
کرتا ہے.قرآنی آیات کی قراءتوں کا اختلاف جو کہ بظاہر بڑا نہیں ہے مگر تا ہم حقیقی اور بنیادی
نوعیت کا ہے.تاریخ تو ہم کھنگال چگے.اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اختلاف قراءت کے مسئلہ پر نظر ڈالتے ہیں.سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ فرق اللہ تعالیٰ کی اجازت کے مطابق تھا.صحیح بخاری میں روایت ہے:
أن رسول الله الله
ﷺ قال أَقْرَأنى جبريل عليه السلام على حَرَفٍ فَلَمْ أَزَلُ
أَسْتَزِيْدُهُ فَيَزِيدُنِي حَتَّى انْتَهَى إِلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ
(بخاری کتاب بدء الخلق باب ذكر الملائكة)
رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ جبرائیل نے مجھے ایک حرف پر قرآن پڑھایا مگر میں اس سے
اس پر مزید وسعت طلب کرتا رہا اور وہ بڑھاتا رہا یہاں تک کہ سات حروف پر جا کر بات ختم ہوئی.پس اس حدیث سے یہ معلوم ہو گیا کہ جو خدائے قدیر قرآن کریم کی حفاظت کا ضامن تھا، قراءت کا فرق اُسی
خدا کی اجازت اور منشا کے مطابق تھا.اس فرق کی اجازت کی حقیقت اور افادیت کیا تھی اور یہ اجازت دینے میں
کیا حکمت کارفر ماتھی یہ تمام امور تاریخ اسلام میں بہت واضح انداز میں بیان ہوئے ہیں.صحیح بخاری کی ہی ایک
دوسری روایت ہے:
حضرت عمر (رضی اللہ عنہ ) فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات
Page 303
قرآن کریم میں تحریف کے الزامات کے جواب
287
مبارکہ میں ایک صحابی ہشام بن حکیم بن حزام (رضی اللہ عنہ ) کوسورۃ الفرقان کی تلاوت کرتے
سُنا.میں نے غور سے سُنا تو معلوم ہوا کہ وہ ایسے انداز میں پڑھ رہے ہیں جو رسول کریم صلی اللہ
علیہ وسلم نے مجھے کبھی نہیں پڑھایا.میں ان
کی نماز مکمل ہونے کا انتظار کرتارہا اور مجھے ان کی نماز
کے اختتام تک بہت صبر سے بیٹھنا پڑا.جب انہوں نے سلام پھیرا تو میں نے ان کو ان کی چادر
سے پکڑ لیا اور پوچھا کہ کہ جو سورۃ میں نے ابھی آپ سے سنی ہے یہ آپ کو کس نے پڑھائی
ہے.انہوں نے جواب دیا کہ رسول کریم نے پڑھائی ہے.میں نے کہا تم غلط کہتے ہو کیونکہ
رسول کریم نے مجھے بھی پڑھائی ہے اور وہ اس طرح نہیں ہے.پس میں انہیں رسول کریم صلی
اللہ علیہ والہ وسلم کی خدمت میں لے گیا اور عرض کی کہ میں نے انہیں قرآن کریم اس انداز میں
پڑھتے ہوئے سُنا ہے جو آپ نے مجھے نہیں پڑھایا.اس پر رسول کریم نے فرمایا اسے چھوڑ دو اور
کہا اے ہشام پڑھو.پھر میں نے بھی اسی طرح تلاوت کی جس طرح میں نے رسول کریم صلی
اللہ علیہ وسلم سے سیکھی تھی.اس پر رسول کریم نے فرمایا کہ اس طرح بھی نازل ہوئی ہے.پھر
فرمانے لگے کہ قرآن کریم سات حروف میں نازل ہوا ہے پس جیسے آسانی محسوس کرو، پڑھ لیا کرو.(بخاری کتاب فضائل القرآن باب انزل القرآن على سبعة حرف)
پھر ایک اور روایت ملتی ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی زندگی میں ہی ایک مرتبہ جب قراءت کا
اختلاف جھگڑے کی صورت میں سامنے آیا تو آپ نے اسے ناپسند فرمایا.چنانچہ بخاری میں ذکر ملتا ہے:
حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ میں نے ایک شخص کو ایک آیت اس انداز میں پڑھتے
ہوئے سُنا جس سے مختلف انداز میں میں نے رسول کریم کو پڑھتے ہوئے سُنا تھا.میں فوراً اس کا
ہاتھ پکڑ کر رسول کریم کی خدمت میں حاضر ہوا.آپ نے فرمایا کہ تم دونوں درست ہوا اور فرمایا
کہ تم سے پہلے جن لوگوں نے اختلاف کیا وہ ہلاک ہوئے.(بخاری کتاب فضائل القرآن باب اقرئوا القرآن ما ائتلف قلوبكم)
قراءت کے اس فرق کی ماہیئت کے بارہ میں صحیح مسلم میں حضرت ابن عباس سے ایک حدیث مروی ہے:
أن رسول الله الله قال أَقْرَأنى جبريل عليه السلام على حَرَف فَرَاجَعْتُهُ
فَلَمْ أَزَلُ أَسْتَزِيْدُهُ فَيَزِيدُنِى حَتَّى انْتَهى إلى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ
إِنَّمَا هِىَ فِى الأمْرِ الَّذِي يَكُونُ وَاحِدًا لَا يَخْتَلِفُ فِي الْحَلَالِ وَلَا الْحَرَامِ
(مسلم کتاب صلاة المسافرين و قصرها باب بیان ان القرآن على سبعة أحرف....یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل نے مجھے ایک حرف پر قرآن
Page 304
الذكر المحفوظ
288
پڑھایا میں اس سے مزید کے لیے کہتا رہا اور وہ بڑھا تا رہا یہاں تک کہ سات حروف تک جا کر
بات ختم ہوئی.ابن شہاب کہتے ہیں کہ اس سے معنی میں فرق نہیں ہوتا تھا اور حلال اور حرام
(یعنی نفس مضمون ) میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا تھا.اس روایت کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت مرزا بشیر الدین محموداحمد صاحب خلیفہ اسی الثانی المصلح الموعود
رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:
اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ قراء تیں جن پر مستشرقین اور پادریوں نے اپنے
اعتراضات کی بڑی بھاری بنیا د رکھی ہے.وہ در حقیقت صرف عرب
کی مختلف اقوام کے لہجوں کا
فرق تھا اور اس قسم کے فرق عربی زبان میں بہت زیادہ پائے جاتے ہیں کیونکہ عرب قوم مختلف
آزاد زبانوں کے اندر گھری ہوئی تھی.عرب کا ایک پہلو حبشہ کے ساتھ ملتا تھا.دوسرا پہلوایران
کے ساتھ ملتا تھا.تیسرا پہلو یہودیوں اور آرامیوں کے ساتھ ملتا تھا اور چوتھا پہلو ہندوستان کے
ساتھ ملتا تھا.ایسے مختلف زبانوں میں گھرے ہوئے لوگوں کی زبان لازماً ان زبانوں سے متاثر
ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی تھی.چنانچہ نتیجہ یہ ہوا کہ بعض عرب بعض حروف کو ادا کر سکتے تھے اور بعض
دوسرے ان حروف کو ادا نہیں کر سکتے تھے.مثلاً بعض لڑ کی جگہ دل ادا کرتے تھے اور بعض دفعہ کسی
لفظ کے ادا کرنے میں مشکل محسوس کر کے اس کے ہم معنی کوئی دوسرا لفظ استعمال کر لیتے تھے.اگر
ایک ادیب اپنی کتاب میں ان دونوں لفظوں کا پڑھنا جائز رکھے تو دونوں قوموں کے لیے اس
کتاب کا پڑھنا آسان ہو جائیگا.مگر دوسری صورت میں ایک حصہ قوم کو اس کا پڑھنا آسان ہوگا
اور دوسرے حصہ قوم کو اس کا پڑھنا مشکل ہوگا اور اگر وہ اسے پڑھے گی بھی تو اپنے اختیار سے
پڑھے گی مصنف کی اجازت سے نہیں پڑھے گی.قرآن کریم نے اس مشکل کو یوں حل کیا کہ جتنے
اختلافات تھے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے قائم مقام حروف یا قائم مقام الفاظ تجویز کر دیے جس کی
وجہ سے تمام اقوام عرب آسانی کے ساتھ قرآن کریم پڑھنے پر قادر ہوگئیں.یہ چونکہ ایک بالکل
اچھوتا اور نیا طریق تھا اور قرآن کریم سے پہلے کسی کا ذہن اس طرف نہیں گیا تھا اس لیے لوگوں پر
شروع شروع میں یہ بات شاق گزرتی تھی اور ہر فریق سمجھتا تھا کہ قرآن میرے قبیلہ کی زبان میں
نازل ہوا ہے.دوسرا قبیلہ اگر لہجہ بدل کر یا حرف بدل کر کسی آیت کو پڑھتا ہے تو وہ گویا قرآن کریم
میں تحریف کرتا ہے.اس لیے شروع میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بار بار سمجھا نا پڑی.جب لوگ سمجھ گئے تو انکو معلوم ہوا کہ یہ عیب نہیں.نہ معنوں میں اس سے کسی قسم کا تغیر پیدا ہوتا ہے
بلکہ بعض دفعہ تو معانی میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے.بعض لوگ بعض حروف پوری طرح ادا
Page 305
قرآن کریم میں تحریف کے الزامات کے جواب
289
نہیں کر سکتے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قراء توں میں قرآن کریم کی تلاوت کی
اجازت دے کر ان تمام اختلافات کو مٹا دیا.اس طرح قرآن کریم ایک عالمگیر کتاب بن گئی جس
کو مختلف لہجہ رکھنے والے عرب بھی آسانی سے پڑھ سکتے تھے اور وہ کہہ سکتے تھے کہ یہ کتاب ہماری
زبان میں ہی نازل ہوئی ہے.اسی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاقرؤا ما
تيسر منه یعنی جو طریق تم پر آسان ہو اس کے مطابق پڑھو.اگر ان حروف کے بدلنے یا ز یرز بر
کے بدلنے سے معانی میں فرق پڑتا تو آپ یہ کیوں فرماتے کہ جس طریق پر پڑھنا تمہیں آسان
ہو، اس طریق پر پڑھ لو.یہ فقرہ صاف بتاتا ہے کہ قراءتوں
کا تعلق صرف تلفظ کے ساتھ ہے معانی
کے ساتھ نہیں اور اگر کسی جگہ تلفظ سے کوئی وسعت بھی پیدا ہوتی ہے تو اصل معنوں میں فرق نہیں
پڑتا.اصل حکم وہی رہتا ہے جو قرآن کریم دینا چاہتا ہے.“
( تفسیر کبیر جلد 6 صفحه 414 زيرتفسیر سورۃ الفرقان نوٹ نمبر 1)
مندرجہ بالا سطور میں بیان فرمودہ حقائق کو مزید وضاحت کی غرض سے الگ الگ دیکھتے ہیں.فرق حرکات (اعراب)
قراءت
کا یہ فرق کبھی صرف زیر زبر کے فرق سے ظاہر ہوتا ہے.ان حرکات (اعراب) کے تغیر سے معنوں پر
کوئی اثر نہیں پڑتا.صرف آسانی کے لیے ہے کہ جس قوم کو جس حرکت سے پڑھنے میں آسانی ہو سکتی ہے وہ اُس
سے پڑھ لیتی ہے.مثلا قریش اور اسد کی زبان میں یائے مضارع کو زبر (-) کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اور چند
دیگر قبائل زیر () کے ساتھ پڑھتے ہیں جیسے يَفْعَل کو يَفْعَل.فرق حروف
اختلاف قراءت کی ایک شکل ادائے حروف کے فرق کی صورت میں تھی.پروفیسر عبدالصمد صارم الازھری اپنی
کتاب تاریخ القرآن میں اختلاف قراءت میں ادائے حروف کے اختلاف کے بارہ میں لکھتے ہیں:
یہ اختلاف صرف ادائے حروف میں تھا.اس سے معنی و مطلب پر کچھ اثر نہیں پڑتا تھا.اہل
یمن سکوت سے بدل دیتے تھے.بجائے ” الناس“ کے ”النات“ بولتے تھے معنی وہی
تھے، اور کوش‘ سے بدلتے تھے.بجائے ” کلام کے غلام بولتے تھے.قبیلہ ہذیل
“ کو ”ع“ سے بدل دیتے تھے اور مٹی کو عشی بولتے تھے.قبیلہ حمیر لام تعریف کو میم سے بدل دیتے تھے.بجائے الشمس و القمر کے الشمس
Page 306
الذكر المحفوظ
290
وامقمر بولتے تھے.قبیلہ قضاعہ کی یائے مشردہ یا مخفہ یا مفتوحہ.ناقل ) کوج سے بدل
دیتے تھے.پیشی کی جگہ مشیج، بولتے تھے.ہاں اس زمانہ میں اس اختلاف سے معنی میں کوئی تغیر
نہیں ہوتا تھا.جیسے ہندوستان میں دہلی والے قلم بولتے ہیں پنجاب والے کلم.حیدر آباد والے
دخلم، معنی ایک ہی ہے.( عربی اور دوسری زبانوں میں فرق یہ ہے کہ دوسری زبانوں میں بولنے
میں تو مختلف ہوتا ہے مگر لکھنے میں ایک طرح لکھا جاتا ہے.مگر عربی میں لکھنے میں بھی فرق ہوتا
ہے) اس
قسم کے الفاظ جن کے اختلاف کی یہ مثالیں نقل کی گئی ہیں، جب غیر ممالک واقوام میں
پہنچتے اور کچھ زمانہ گذر جاتا تو کیا ہوتا؟ مصحف عثمانی سے بعض صحابہ کے اس اختلاف کی مثال
حدیث میں بتائی گئی ہے.قریش تابوت بولتے تھے اور زید بن ثابت تا بوہ کہتے تھے.(عبدالصمد صارم الازھری: تاریخ القرآن ، ایڈیشن 1985 ندیم یونس پرنٹر ز لا ہور، پبلشرز :
مکتبہ معین الادب اردو بازار لا ہور صفحہ 82،81)
اس کی بہت سی مثالیں ہیں.مثلاً
د
بنو تمیم لفظ کے پہلے ' کو 'ع' سے بدل دیتے ہیں.جیسے اسلم کو عسلم
بنو ہذیل 'ح' کو 'ع' سے بدل دیتے ہیں.جیسے 'حرب' کو 'عرب
بنو قضاعہ لفظ کی آخری 'ی' کو 'ج' سے بدل دیتے ہیں.جیسے تمیمی کو ہیج،
نبوسعد 'ع' کو 'م سے بدل دیتے ہیں.جیسے عطی' کو مطی
عام عربی میں جگ نہیں بولتے مگر بنو تمیم گ بولتے ہیں.اور اہل مصر عام طور پر حرف 'ج' کو حرف گ
سے بدل کر ادا کرتے ہیں.اس طرح وہ 'ثلج، کوٹلگ کہتے ہیں اور جمیل کو گمیل“ کہتے ہیں.ربیعہ اور مصر مؤنث میں ک، خطاب کے بعد 'ش' بڑھا دیتے ہیں جیسے 'علیک‘ کو علیکش“
پھر میری زبان والے الفاظ کو کسی قدر کھینچ کر ادا کرتے ہیں جیسے یا ابن العم کو یا بن معم
اسی طرح شمالی اور جنوبی عرب میں اختلاف کی ایک شکل یہ ہے کہ شمالی عرب میں علامت جمع دن ہے جبکہ
جنوبی عرب میں دم ہے.اسی طرح شمالی عرب میں حرف تعریف ہے جبکہ جنوبی عرب میں دم ہے.شمالی اور جنوبی عرب کی زبانوں میں حروف کے ادائیگی کے اختلاف کی وضاحت عربی عبارت کی اس مثال
سے ہو جاتی ہے :
جنوبی عرب
وهم
واجهو
بنو كلبت
هقنوا
المقه
شمالی عرب
وهب
و اخوه
بنو کلبه
اقنوا
المقه
Page 307
قرآن کریم میں تحریف کے الزامات کے جواب
291
جنوبی عرب
ذمرن
ذن
مزندن
و قههو
شمالی عرب
ذامران
ذا
اللوح
لانه
وقاهم
جنوبی عرب
بمسالهو
لوفيهم
وسعدهم
نعمه
شمالی عرب
بماسالوه
ووفاهم
واسعدهم
منه
ارض القرآن از سید سلیمان ندوی.دارالاشاعت کراچی حصہ دوم صفحہ 352)
اختلاف لغت
اختلاف قراءت کی ایک شکل ایسی ہے جس میں ایک ہی لفظ مختلف قبائل میں مختلف معنوں میں رائج ہوتا
ہے.چنانچہ شمالی اور جنوبی عرب کی زبانوں میں ایک جیسے الفاظ کے معانی میں زمین اور آسمان کا فرق ہے.مثلاً
لفظ
زو
جنوبی عرب
بادشاہ
قلعه
شمالی عرب
والا ( ذوالقرنین : سینگوں والا )
مستقل آبادی خواہ گاؤں ہو یا شہر
ارض القرآن از سید سلیمان ندوی.دارالاشاعت کراچی حصہ دوم صفحہ 354)
حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب خلیفہ اسیح الثانی الصلح الموعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مکہ
میں ایک امیر عورت رہا کرتی تھی جس کا ایک یمنی ملازم تھا.وہ عورت حقہ کی عادی تھی.مکہ میں عام رواج تھا کہ
حقہ کا وہ حصہ جس میں پانی ہوتا ہے شیشہ کا بنایا جاتا ہے اور اسی نسبت سے اسے شیشہ ہی کہتے ہیں.اس عورت
نے اپنے ملازم سے کہا کہ "غیر الشيشة ملازم نے پہلے تو اپنی طرف سے وفاداری سے کام لیتے ہوئے
اپنی مالکہ کو پورے ادب کے ساتھ حکم واپس لینے کی درخواست کی.مگر پھر مالکہ کے ناراض ہونے پر کہ وہ کیوں
اس کا حکم نہیں مانتا ملازم نے باہر جا کر حقہ کا شیشہ توڑ دیا.اس پر مالکہ نے اسے بُرا بھلا کہا کہ تم نے ایسا کیوں
کیا.ملازم حیران تھا کہ اس نے تو پہلے ہی ایسا حکم ماننے میں پس و پیش کی مگر مالکہ کے ناراض ہونے پر اسے حکم
مانا پڑا.اب جب حکم مان لیا ہے تو مالکہ پھر ناراض ہو رہی ہے.اس پر ایک واقف کار نے بتایا کہ تم اسی حجازی
زبان میں کہ رہی ہو کہ غير الشيشة.یعنی حقے کا پانی بدل دو اور یمنی میں اس کا مطلب ہے کہ شیشہ توڑ دو.پس اس نے وہی کیا جو وہ سمجھا تھا.( تفسیر کبیر جلد نم صفحہ 49 زیر آیت الیل :4)
پس اگر ایک قبیلہ کے سامنے دوسرے قبیلہ کی زبان بولی جاتی تو سمجھنے میں مشکل کا امکان ہوتا تھا.یا پھر معانی
بدل جانے کا امکان ہوتا تھا.چنانچہ اس قسم کے
قبائلی لغوی اختلافات کو آنحضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی باریک بین نظر
Page 308
الذكر المحفوظ
292
نے بھانپ لیا اور جب جوق در جوق عرب کے مختلف قبائل حلقہ بگوش اسلام ہونے لگے تو آپ نے قرآن کریم کی
معنوی حفاظت اور کثرت اشاعت کے لیے الہی منشاء اور اجازت کے تحت قرآن کریم مختلف قراء توں میں سکھایا تا کہ
مختلف عرب قبائل اپنی اپنی آسانی کے مطابق قراءت اختیار کر لیں اور زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تعلیمات سے
روشناس ہوں اور تا کہ قرآن کریم کی تعلیمات کی کثرت سے اشاعت ہو جائے.اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ قرآن
کریم کی تفہیم اور درست تفسیر کے لیے قراءت ایک اہم ذریعہ ثابت ہونے لگی.چنانچہ اسی فائدہ کی طرف اشارہ
فرماتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دوسری قراءت کو حدیث صحیح کے قائمقام قرار دیا.( براہین احمدیہ حصہ پنجم روحانی خزائن جلد 21 صفحہ 410)
چنانچہ اس قسم کے لغوی اختلاف کو بھی مخالفین اور مستشرقین اپنی جہالت سے یا دھوکہ کی غرض سے سادہ لوح
لوگوں کو بہکانے کے لیے پیش کرتے ہیں.حالانکہ قرآن کریم کی معنوی حفاظت کے لیے اور نئے عربی مسلمانوں
کی آسانی کے لیے عین مناسب تھا کہ ابتداء میں ہر قبیلہ کو اس کی زبان کے معانی کے مطابق قرآن کریم کے
وہ الفاظ جو ان کے لیے سمجھنے یا ادا کرنے مشکل تھے یا ان کے قبیلہ میں ان الفاظ کے معانی اُن معانی سے مختلف
تھے جن معانی میں یہ الفاظ قرآن کریم میں استعمال ہو رہے تھے تو اُن الفاظ کے مترادف الفاظ سکھا دیے جاتے.اور آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے الہی اجازت اور منشاء کے تحت ایسا ہی کیا.اگر ایسا نہ ہوتا تو نومسلم عرب میں
قرآن کریم کی تعلیم اتنی سرعت سے نہ پھیلتی جتنی سرعت سے پھیلی.گزشتہ سطور میں درج روایات سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ صحابہ کو حفاظت قرآن کا کس قدر خیال تھا اور
کس توجہ سے وہ قرآن کریم کی تلاوت سنتے تھے اور کس طرح چھوٹی سی چھوٹی اونچ نیچ بھی فور رسول کریم صلی اللہ
علیہ والہ وسلم کور پورٹ کی جاتی تھی.پھر یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ مختلف قراءتوں میں تلاوت کی اجازت دینے کی وجہ
محض یہ تھی کہ عربوں کو قرآن سیکھنے اور سکھانے میں آسانی مہیا کی جائے.جہاں بھی اختلاف کی صورت پیدا ہونے
کا اندیشہ ہوتا وہاں صحابہ فوراً رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے فیصلہ لے لیتے.رسول کریم قراءتوں کے اختلاف
کو اہمیت نہیں دیتے بلکہ اختلاف کرنے سے روکتے تھے.کیونکہ عربی ماحول میں یہ اختلاف کوئی اختلاف نہیں تھا.اختلاف قراءت کے حوالہ سے یہ حقیقت بھی مد نظر رہنی ضروری ہے کہ اس کی اجازت اس وقت دی گئی جس
وقت تک تقریباً مکمل قرآن کریم نازل ہو جا چکا تھا اور آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر نگرانی تحریری صورت میں
اور حفظ کے ذریعہ محفوظ ہو چکا تھا.اس اجازت کے بعد بہت قلیل حصہ نازل ہوا.اگر ہم حتمی طور پر اس اجازت
کے وقت کی تعیین کرنا چاہیں تو سب سے پہلے تو یہ مد نظر رکھنا ضروری ہوگا کہ مکی دور میں اختلاف قراءت کی
اجازت نہیں تھی اور نہ ہی کبھی ایسا ہوا.چنانچہ مکی دور میں اسلام قبول کرنے والے کبار صحابہ، مثلاً حضرت عمرؓ اور
حضرت عبداللہ بن مسعود وغیرہ نے اختلاف قراءت پر آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مدنی دور میں فیصلہ لیا تھا اور اُن
Page 309
قرآن کریم میں تحریف کے الزامات کے جواب
293
واقعات کے مطالعہ سے واضح ہوتا ہے کہ وہ اس اجازت سے بالکل نابلد تھے اور اس پر بہت حساس رویہ دکھایا تھا.مدنی دور میں یہ اجازت کب ہوئی اس کا بہت محتاط اندازہ حضرت عمرؓ کے حوالہ سے تاریخ میں مذکور اختلاف قراءت
والی روایت سے آسانی سے لگایا جاسکتا ہے.حضرت عمر کو پہلی مرتبہ اختلاف قراءت کا علم حضرت حکیم بن ہشام
بن حزام کے سورۃ الفرقان کی تلاوت کرنے سے ہوا.یہ نہایت مستند اور معتبر روایت ہے اور بخاری اور مسلم
دونوں میں درج ہے.حضرت حکیم بن ہشام بن حزام نے نو ہجری میں اسلام قبول کیا.اس معلوم ہوا کہ یہ واقعہ
نو ہجری کے بعد کا ہے جب کہ پہلی مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے علم میں اختلاف قراءت کا مسئلہ آیا.اب تاریخ
اسلام سے واقف شخص جانتا ہے کہ حضرت
عمر ہمہ وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے
تھے اور یہ ناممکن تھا کہ قرآن کریم کے حوالہ سے کسی نئی بات کا آپ کو دیر سے علم ہوتا.پس یہ واقعہ لازماً اس
اجازت کے فوراً بعد کا ہی ہے.نیز یہ بھی مد نظر رہے کہ حضرت حکیم بن ہشام بن حزام کے قبول اسلام کے فوراً
بعد اگر آپ سے تلاوت قرآن کریم میں کسی قسم کی غلطی ہوتی تو بطور نو مسلم حضرت عمرؓ آپ سے نرمی کا رویہ اختیار
کرتے مگر ایسا نہیں ہوا.صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ آپ کے قبول اسلام سے کافی بعد کا ہے.اس پر ایک قرینہ
یہ بھی قائم ہوتا ہے کہ سورۃ الفرقان لمبی سورتوں میں شمار ہوتی ہے.پس حضرت حکیم بن ہشام بن حزام کو اسلام
قبول کیے ہوئے اتنی دیر ضرور ہو چکی تھی کہ آپ نے قرآن کریم کی یہ لمبی سورت یاد کر رکھی تھی.بہر حال زیادہ سے
زیادہ اس اجازت کا زمانہ نو ہجری ہی قرار دیا جا سکتا ہے.اور قرین قیاس ہے کہ نو ہجری کے بھی کافی بعد یہ اجازت
ہوئی ہو لیکن اس سے پہلے نہیں.یعنی ساڑھے بائیس سال سے زائد عرصہ نزول میں سے اکیس سال سے زائد عرصہ
تک ایک ہی قراءت میں پڑھا جاتا تھا اور ان اکیس سالوں میں تقریباً سارا قرآن کریم نازل ہو چکا تھا.ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے عرب کے مختلف قبائل کی لغات میں بے شک فرق تھا اور اس وجہ سے قرآن کریم کی
قراءت میں فرق کرنے کی اجازت بہت معقول لگتی ہے مگر حضرت عمرؓ اور حضرت حکیم بن ہشام کے اختلاف کا
تعلق اس اجازت سے نہیں ہوسکتا.کیونکہ حضرت عمر اور حضرت حکیم بن ہشام، دونوں ایک ہی قبیلہ کے تھے اور
اُن دونوں کی زبان میں یہ فرق نہیں ہو سکتا.پس اُن دونوں کے اختلاف کا قراءت کے فرق سے تعلق نہیں ہوسکتا.اس ضمن میں یہ ذہن نشین رہنا چاہیے کہ اختلاف قراءت کی اجازت اُس وقت ہوئی جب کہ کثرت سے
لوگ حلقہ بگوش اسلام ہورہے تھے.اسی دور میں حضرت حکیم بن ہشام نے بھی اسلام قبول کیا.پس عین ممکن
ہے کہ آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اُس وقت سورۃ الفرقان سیکھی ہو جب کہ آپ کسی دوسرے قبیلہ
کے مسلمان ہونے والوں کو سکھا رہے ہوں.پھر یہ بھی ممکن ہے کہ مختلف قبائل کے کثرت سے قبول اسلام اور مدینہ میں اُن کے نمائندوں کے کثرت سے
Page 310
الذكر المحفوظ
294
اجتماع کی وجہ سے ایک قبیلہ کی لغت کو کوئی دوسرے قبلہ کا شخص سیکھ جائے.حج کے دنوں میں تو سارے عرب کے
قبائل مکہ میں جمع ہوتے تھے اس لیے قریش کے لوگوں کی دوسرے عرب قبائل کی لغات سے واقفیت کوئی اچھنبے کی
بات نہیں اس لیے یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت حکیم بن ہشام اپنے قبیلہ کی لغت کے ساتھ ساتھ دوسرے کسی قبیلہ کی
لغت کے بھی ماہر ہوں.حضرت عمرؓ نے بھی قرآن کریم کے حوالہ سے حساس رویہ دکھایا.روایت سے کوئی ایسا نتیجہ تو نہیں نکلتا کہ آپ
اُس لغت سے واقف ہی نہ ہوں.ہاں اس رویہ سے یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ اُس وقت آپ اس اجازت سے
واقف نہ تھے.گویا یہ اجازت اس واقعہ کے تھوڑا پہلے ہی ہوئی تھی.عین ممکن ہے کہ یہ اجازت ایک دن پہلے ہوئی
ہو.کیونکہ روایات میں یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ حضرت عمرؓ ایک دن چھوڑ کر ایک دن آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی
خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے.آپ نے ایک اور صحابی کے ساتھ یہ معاہدہ کر رکھا تھا کہ ایک دن وہ
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر رہیں گے اور حضرت عمر کو اُس دن کے واقعات سے آگاہ کریں گے اور
ایک دن حضرت عمر پیارے آقا کی صحبت میں رہیں گے اور اُن صحابی کو اہم واقعات سے آگاہ کریں گے.ہوسکتا
ہے جس دن اختلاف قراءت کی اجازت ہوئی ہو اُس دن دوسرے صحابی کی باری ہو اور یا تو وہ اپنی باری والے
روز رسول کریم کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکے ہوں اور یا پھر اُن کی حضرت عمرؓ سے ملاقات نہ ہوئی ہو.واللہ اعلم.پس حضرت عثمان نے اپنے دور میں بوجوہ اس اختلاف کو ختم کرنے کا حکم جاری کردیا اور استثنائی حالات میں
آسانی کی خاطر دی گئی اس اجازت کو موقوف کر دیا.اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ طریق فائدہ مند تھا اور
سب سے بڑھ کر منشاء الہی کے مطابق تھا تو پھر کیوں بعد میں اس انداز کوختم کر دیا گیا؟
اس کی وجہ یہ بنی کہ حضرت عثمان کے زمانہ میں اسلام عرب اور غیر عرب بہت سے علاقوں میں پھیل چکا تھا.حضرت عثمان کے دور تک تو مختلف قبائل اپنی اپنی قراءت میں آسانی سے قرآن کریم کی درس و تدریس اور اشاعت
کر لیتے تھے.مگر جب مختلف قبائل کے لوگ آپس میں ملتے تو ان میں سے وہ جو دوسرے قبیلہ کی زبان کا گہرائی سے علم
رکھتے تھے، الجھ جاتے اور سمجھ بیٹھتے کہ گویا قرآن کریم کی غلط تلاوت کی جارہی ہے.یہ مسئلہ جب رسول کریم صلی
اللہ علیہ وسلم کے دور میں سامنے آتا تو آپ سمجھا دیتے اور اس بارہ میں اختلاف کرنے سے منع فرماتے.لیکن حضرت
عثمان کے دور میں کثرت اختلاف اور نومسلم عربوں کی مشکلات حل کرنے کے لیے یہ بہتر سمجھا گیا کہ اب ایک قراءت
ہونی چاہیئے.پھر اختلاف قراءت کو ختم کرنے کی ایک اہم وجہ یہ تھی کہ بہت سی دوسری اقوام کے اسلام قبول کرنے کے
باعث قرآن کریم عرب کے قبائل سے باہر نکل کر عالمی تعلیم کے طور پر رائج ہورہا تھا اور غیر عرب نومسلموں کے لیے
اختلاف قراءت کے باعث قرآن کریم سیکھنا دشوار تھا اور نہ صرف دشوار تھا بلکہ عربوں کی نسبت زیادہ غلط فہمی کا امکان تھا
Page 311
قرآن کریم میں تحریف کے الزامات کے جواب
295
اور مخالفین بھی اپنے مزموم مقاصد میں اس غلط نہی کو استعمال کر سکتے تھے.اس طرح مختلف قراء توں کا جو مقصد تھا یعنی
آسانی اور کثرت اشاعت، وہ فوت ہو گیا تھا.اب تک تو حفاظت قرآن کے حوالہ سے صحابہ حساس رویہ دکھاتے مگراب
بہت سے عرب ایسے تھے جو نو مسلم ہونے کی وجہ سے اعلیٰ اسلامی اخلاق پر کار بند نہ تھے اور بجائے مقصد کی طرف دیکھنے
کے قبائلی عصبیت کی بنا پر اختلاف شروع کر دیتے.چنانچہ جو کام آسانی کے لیے شروع کیا گیا تھا وہ اپنا مقصد کھو رہا تھا
اور مشکل پیدا کر رہا تھا اور ایک سے زیادہ قراء تیں قرآن کریم کے بارہ میں امتِ مسلمہ کے اتفاق اور اتحاد کے لیے خطرہ
بن گئی تھیں.پس اب اختلاف قراءت میں قبیلوں کی لغات کا اختلاف آسانی کا سبب کم بن رہا تھا اور نقصان کا اندیشہ
زیادہ تھا.لوگوں کی توجہ بجائے اس مقصد کے حصول کی طرف ہونے کے، جس کی خاطر قرآن کریم نازل کیا گیا تھا،
اختلاف کی طرف ہورہی تھی اس لیے اس اختلاف
کو ختم کر دیا اور مرکزی قراءت قریش کی تمام عالم اسلام میں رائج
کر دی گئی.گویا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں جو وجہ قراءت کے فرق کو رواج دینے کی بنی اب وہی وجہ
اس فرق
کو ختم کرنے کی بھی بنی.یعنی پہلے ہم تعلیم قرآن میں آسانی پیدا کرنے کے لیے اجازت دی گئی اور اب آسانی
پیدا کرنے کے لیے یہ اجازت واپس لے لی گئی.پس حضرت عثمان نے صحابہ کے مشورہ سے یہ فیصلہ فرمایا کہ اب وقت
آ گیا ہے کہ قرآن کریم کے بارہ میں امت کی زبان کو بھی وحدت پر جمع کر دیا جائے.چنانچہ آپ نے جب مصحف ام
کی قراءت واحدہ پر امت کو جمع کرنے کے لیے صحابہ سے رائے لی تو سب نے کہا کہ آپ کی رائے بہترین ہے.(فتح الباری شرح صحیح بخاری کتاب فضائل القرآن باب جمع القرآن جلد 9)
چنانچہ حضرت عثمان نے حضرت حفصہ کے پاس محفوظ مصحف ام ، جو حضرت
ابوبکر کے دورِ خلافت میں صحابہ کی
گواہی سے جمع کیا گیا تھا اور جس پر تمام امت کو اطمینان تھا، قریش کے طرز تحریر کے مطابق شائع کر دیا.(بخاری
كتاب فضائل القرآن باب جمع القرآن ) اور اس میں کسی قسم کا تغیر اور تبدل نہیں کیا.چنانچہ آپ فرماتے ہیں
کہ میں قرآن مجید میں ایک حرف کی تبدیلی بھی روا نہیں رکھتا.(بخاری كتاب التفسيـر بـاب والذين يتوفون و
يذرون منكم ازواجاً) آپ نے مصحف ام سے سات صحائف تیار کرائے ایک اپنے پاس رکھا اور باقی چھ نسخے
بلا داسلامیہ میں پھیلا دیے اور ان کے ساتھ ایک ایک قاری بھی بھیجا جو ان علاقوں میں ایک انتظام کے تحت
لغت قریش کے مطابق قرآن کریم کی تعلیم دیتا.اس متن کو اب مرکزی سمجھا گیا اور باقی تمام صحائف ایک نظام کی نگرانی میں ضائع کر دیے گئے.اس وقت سے
لے کر آج تک قرآن کریم کے مستند نسخے انہی مصاحف کے مطابق تیار کیے جاتے ہیں.حضرت علی فرماتے ہیں:
لولم يصنعة لصنعته
(كتاب المصاحف الجزء الاول صفحه 12)
یعنی اگر حضرت عثمان ایسا نہ کرتے تو پھر میں ایسا کرتا.
Page 312
الذكر المحفوظ
296
ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں:
”اے لوگو! عثمان کے بارہ میں غلو سے بچو.یہ نہ کہو کہ انہوں نے قرآن کریم کو جلایا.بخدا
انہوں نے اسے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی سے جلایا.انہوں نے ہمیں اکٹھا کیا
اور پوچھا کہ تم قرآن میں اختلاف قراءت کے بارہ میں کیا کہتے ہو؟ ہم نے کہا آپ کی کیا رائے
ہے.آپ نے فرمایا: میں چاہتا ہوں کہ تمام لوگوں کو ایک قراءت والے مصحف پر جمع کردوں کیونکہ
آج اگر تم اختلاف میں پڑ گئے ہو تو تمہارے بعد لوگ اس سے زیادہ اختلاف میں پڑ جائیں گے.ہم نے عرض کیا آپ کی رائے ہی بہترین رائے ہے اور ہمیں اس سے اتفاق ہے.“
(فتح البارى كتاب فضائل القرآن باب جمع القرآن جزء 9)
( ابی عبدالله الزنجانی: تاریخ القرآن زیر عنوان القرآن فی عہد عثمان صفحه 46)
یہاں یہ سوال اٹھتا ہے کہ مصحف ام کس قراءت پر لکھا گیا تھا ؟ مصحف ام اور مصحف الامام کی قراءت ایک
ہی تھی یا مختلف قراء تیں تھیں؟
مصحف ام لغت قریش پر لکھا گیا تھا.اس ضمن میں سب سے پہلے تو ہم مذکورہ بالاحوالہ کی طرف قاری کی توجہ مبذول
کرواتے ہیں جہاں حضرت عثمان کا یہ قول درج ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تمام لوگوں کو ایک قراءت والے مصحف
پر جمع کر دوں اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ مصحف ام کی ایک ہی قراءت تھی اور وہ لامحالہ قراءت قریش تھی.اس ضمن میں یہ یاد رہنا چاہیے کہ اختلاف قراءت کی اجازت صرف تلاوت سے تعلق
رکھتی تھی.چنانچہ
آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان فقرؤا ما تيسر منه (جس طرح آسانی ہو اس طرح پڑھو ) اس امر کی دلیل
ہے.آنحضور نے کتابت کے بارہ میں نہیں فرمایا تھا کہ جس طرح آسانی ہو لکھ لوصرف تلاوت کے بارہ میں فرمایا کہ جس
طرح آسانی ہو اس طرح پڑھ لو.لکھنے کے بارہ میں تو اسقدر احتیاط تھی کہ ایک مرتبہ حکما تحریرات جلوادیں.نو ہجری کے لگ
بھگ جب یہ اجازت دی گئی تو تقریباً سارا قرآن
کریم تحریر اور حفظ کی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر نگرانی
لغت قریش محفوظ کیا جاچکا تھا.پس لازماً آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی عرصہ کے دوران نازل ہونے والی آیات
بھی اسی قراءت میں لکھوائی ہوں گی.اگر یہ تسلیم کر بھی لیا جائے کہ قرآن کریم کی تحریر میں اختلاف قراءت ہوگا تو یہ نو بجری
کے بعد نازل ہونے والی چند آیات کی تحریر میں ہوگا.لیکن قرین قیاس یہی ہے کہ باقی قرآن کریم کی طرح نو ہجری
کے بعد نازل ہونے والی آیات بھی آپ نے لغت قریش میں ہی لکھوائی تھیں.چنانچہ نزول کے حساب سے جو سب سے
آخری آیت ہے وہ آج کے دور میں لغت قریش کے مطابق شائع ہونے والے نسخہ ہائے قرآن کریم میں اسی طرح
پائی جاتی ہے جس طرح نزول کے فوراًبعد آنحضور کے دور میں لکھی گئی.حضرت ابو بکڑ نے جو نسخہ تحریر کروایا اس میں اس
بات کا خاص خیال رکھا کہ اس کی بنیا د رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رو بر وتحریر کی گئی یا آپ سے تصدیق شدہ
Page 313
قرآن کریم میں تحریف کے الزامات کے جواب
297
تحریرات ہی بنائی جائیں.پھر حضرت عمرؓ نے مصحف ام کی تیاری کے وقت یہ نصیحت بھی فرمائی تھی کہ خاندان مضر کی
لغات پر قرآن کریم تحریر کیا جائے.(کتاب المصاحف جزء اول صفحہ 11) قریش خاندان مضر کی ہی ایک شاخ تھی
اس لیے مصحف امام کی تیاری کے وقت زیادہ اختلاف بھی نہیں ہوا اور حضرت عثمان نے مصحف ام کو بعینہ نقل کر دیا.چنانچہ مستند اور معتبر روایات کے مطاق حضرت عثمان نے مصحف ام سے جو صحیفہ تیار کروایا اس میں صرف ایک اختلاف
ہوا تھا جو کہ ایک لفظ تابوت کی محض طرز تحریر کا اختلاف تھا.اس اختلاف کے بارہ میں یقینی طور پر نہیں کہا جاسکتا کہ
یہ کا تب وحی حضرت زید اور باقی صحابہ کا اختلاف تھایا اس نئے نسخہ کا مصحف ام سے اختلاف تھا.ایک اور بہت مضبوط قرینہ اس بات پر کہ مصحف ام لغت قریش پر تھا یہ ہے کہ جب حضرت عثمان نے
مصحف الامام کی تیاری کے بعد باقی صحائف جلانے کا حکم دیا تو مصحف ام جلانے کی چنداں ضرورت نہ سمجھی.اگر مصحف ام
کا مصحف امام سے اختلاف تھا تو پھر رفع اختلاف کی خاطر دیے گئے حکم کے تحت باقی صحائف کے
ساتھ مصف ام کو بھی جلا دینا چاہیے تھا.سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر مصحف ام لغت قریش پر ہی تحریر کیا گیا تھا تو حضرت عثمان نے قراءتِ واحدہ پر جمع
کرنے کے لیے جو ہدایات دیں ان میں یہ بھی ہدایت دی کہ اگر کسی لفظ کے بارہ میں اختلاف ہو تو پھر قریش کی
لغت پر لکھ لو.(بخاری کتاب فضائل القرآن باب جمع القرآن) اس سے کیا مراد ہے؟
اس ضمن میں عرض ہے کہ اس سے مراد انداز تحریر کا اختلاف ہے.مصحف امام کی تیاری کے لیے حضرت عثمان
نے جو کمیٹی بنائی اس میں حضرت زید مدنی تھے اور باقی صحابہ قریش سے تعلق رکھتے تھے.حضرت زید کا انداز تحریر
اور قریش کا انداز تحریر مختلف تھا اور قرآن کریم قریش کی لغت میں نازل ہوا تھا اس لیے اس کا انداز تحریر قریش کے
مطابق ہونا چاہیے تھا.چنانچہ بخاری کی ہی ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ اگر
قرآن کریم کی عربی میں کوئی اختلاف ہو تو قریش کی عربی پر لکھو.اب جب کام کتابت کا ہورہا تھا تو پھر اس
ہدایت کا تعلق بھی کتابت سے ہی ہو سکتا ہے.چنانچہ جو ایک اختلاف ہوا وہ بھی اسی امر کا مؤید ہے کہ یہ ہدایت
اسلوب تحریر کے انداز کے حوالہ سے تھی.اختلاف یہ تھا کہ لفظ ” تابوت حضرت زیڈ کے قبیلہ کی زبان میں
بجائے ” کے کے ساتھ لکھا جاتا تھا.جب یہ اختلاف ہوا تو حضرت عثمان نے فیصلہ فرمایا کہ تابوت لکھا
جائے کیونکہ قریش کے ساتھ لکھتے ہیں.جب مصحف امام تیار ہو گیا تو حضرت عثمان نے اسکا جائزہ لینے کے
بعد فرمایا کہ اگر املاء کروانے والا والا ھذیل قبیلہ کا ہوتا اور لکھنے والا بنو ثقیف کا ہوتا تو جو فرق رہ گئے ہیں وہ بھی نہ
رہتے.اس فرمان سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ فرق صرف تحریر کے تھے.مستند روایات میں اکا دکا اختلاف کا ذکر ملتا
ہے اور سب غیر مستند روایات کو بھی شمار کر لیا جائے تو اُن کے مطابق حضرت عثمان کے صحیفہ میں اس طرح کی کل
بارہ تبدیلیاں کی گئیں جو سب کی سب ایسی ہی معمولی لفظی تبدیلیاں تھیں جن سے معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا.66
Page 314
الذكر المحفوظ
298
پس مصحف ام لغت قریش پر تحریر کیا گیا تھا اور حضرت عثمان نے اس کی نقول تیار کراتے وقت یہ خیال رکھنے
کی ہدایت فرمائی کہ گو مصحف ام لغت قریش پر ہے مگر چونکہ حضرت زید قریشی نہیں ہیں اس لیے اسلوب تحریر میں
فرق ہوسکتا ہے.پس باقی صحابہ اس بات کا خیال رکھیں کہ اسلوب
تحریر بھی قریش کا ہی ہو.حضرت عثمان نے جو نقول کروائیں ان کا حضرت حفصہ کے پاس محفوظ اصل نسخہ سے کبھی کوئی اختلاف
ثابت نہیں ہوا حالانکہ حضرت حفصہ کا نسخہ حضرت عثمان کے زمانے کے بہت بعد مروان بن عبدالملک کے دور تک
رہا.اس دور میں مخالفوں کا اور حفاظ کا اور دوسرے علماء کا کوئی اختلاف نہ کرنا بتاتا ہے کہ قرآن کریم کا متن بعینہ
وہی تھا جو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے جمع کردہ مصحف ام کا تھا اور جس کے بارہ میں صحابہ کی متفقہ گواہی موجود تھی
کہ یہ نسخہ وہی ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی نوع کو دیا تھا.مصحف امام کی تیاری کے وقت اس بات کا خاص خیال رکھا گیا کہ ہر لفظ کو اس طرح تحریر کیا جائے کہ زیادہ سے
زیادہ قراء تیں متن میں سمودی جائیں.پس آج کے دور میں امت مسلمہ میں اس بات کا خاص خیال رکھا جاتا ہے کہ
قرآن کریم کی اشاعت کے وقت اس کا متن مصحف امام کے عین مطابق ہو اور لفظ کو بعینہ اسی طرح انہی حروف کے
ساتھ درج کیا جائے جس طرح حضرت عثمان کے دور میں مصحف امام یا اس سے تیار کی گئی نقول میں درج کیا گیا تھا.پس حضرت عثمان نے اس صحیفہ کو لاگو کر دیا جس پر امت حضرت ابوبکر کے دورِ خلافت میں
متفق ہوئی تھی.اب امت کی ذمہ داری تھی کہ جس صحیفہ کی انہوں نے متفقہ طور پر تصدیق کی تھی کہ یہ وہ قرآن ہے جو رسول کریم
سے انہوں نے سیکھا تھا، اس کو اختیار کریں اور مختلف قراء توں کو جو کہ اختلاف کا سبب بن رہی ہیں، چھوڑ دیں
کیونکہ جس فائدہ کے لیے وہ اختیار کی گئیں تھیں وہ فائدہ اب نہیں رہا تھا بلکہ اب نقصان کا اندیشہ تھا.پس
حضرت عثمان نے اس کے سوا کوئی نیا کام نہیں کیا تھا.حضرت خلیفتہ امسیح الاول فرماتے ہیں:
لوگ حضرت عثمان کو جامع القرآن بتاتے ہیں.یہ بات غلط ہے.صرف عثمان کے لفظ
کے ساتھ قافیہ ملایا ہے.ہاں شائع کنندہ قرآن اگر کہیں تو کسی حد تک بجا ہے.آپ کی خلافت
کے زمانہ میں اسلام دُور دُور تک پھیل گیا تھا.اس لیے آپ نے چند نسخہ نقل کرا کر مکہ ، مدینہ،
شام، بصرہ ، کوفہ اور بلاد میں بھجوا دیئے تھے اور جمع تو اللہ تعالیٰ کی پسند کی ہوئی ترتیب کے ساتھ
نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ہی فرمایا تھا اور اسی پسندیدہ ترتیب کے مطابق ہم تک پہنچایا
گیا.ہاں اس کا پڑھنا اور جمع کرنا ہم سب کے ذمہ ہے.“
(ضمیمہ اخبار بدر قادیان.14اپریل 1912 ء بحوالہ حقائق الفرقان جلد 4 صفحہ 272)
اختلاف قراءت کے ضمن میں یہ امر بھی یادرکھنا چاہیے کہ صحابہ قرآن
کریم کی تفسیر اور تشریح میں جو الفاظ یا جملے بیان
Page 315
قرآن کریم میں تحریف کے الزامات کے جواب
299
فرماتے تھے انہیں اس فرق سے الگ رکھنا چاہیے جسے حضرت عثمان نے ختم فرمایا.وہ دراصل تشریحات تھیں جو صحابہ
درس و تدریس کے دوران لوگوں کو قرآن کریم کے معانی سکھانے کے لیے کیا کرتے تھے.صحابہ کی زبان کیونکہ عربی
تھی اس لیے لازماً تشریح بھی عربی میں ہی کیا کرتے تھے.ان تفسیری حواشی کو بھی صحابہ قراءت کا نام ہی دیا کرتے
تھے کہ یہ فلاں صحابی کی قراءت ہے اور اس سے مراد یہ ہوتی تھی کہ یہ فلاں صحابی کی تفسیر ہے.چنانچہ سنن ترمذی
ابواب تفسير القرآن عن رسول الله باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برایہ میں مجاہد کا قول درج ہے کہ:
عن الاعمش قال قال مجاهد لو كنت قرأت قرائة بن مسعود لم احتج
الى ان اسأل ابن عباس عن كثير مما سألت (رقم الحديث : 2886)
یعنی اعمش کہتے ہیں کہ مجاہد فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں نے حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ
کی قراءت پڑھی ہوتی تو بہت سی باتیں جو مجھے ابن عباس سے پوچھنا پڑیں نہ پوچھنا پڑتیں.اس سے صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ قراءت سے تفسیر بھی مراد ہوتی تھی اور صحابہ کا بھی تفسیر میں اختلاف رائے ہوا
کرتا تھا.مستشرقین عدم
علم یاد جل کی راہ سے اختلاف کے قراءت کے موضوع پر سوالات اُٹھاتے ہوئے اس تفسیری
اختلاف کو بھی پیش کر دیتے ہیں لیکن یہ صرف اُن کی جہالت ہے یا پھر اُن کا دجل جس سے ناواقف انسان دھو کہ کھاتا ہے.پس یہ معاملہ واضح ہے اور صرف فریبی اور جھوٹا شخص ہی اس سے شبہ پیدا کرنے کی کوشش کر سکتا ہے اور صرف
ناواقف انسان ہی اس سے دھو کہ کھا سکتا ہے ورنہ قرآن کریم کی حفاظت کے بیان میں اختلاف قراءت کا باب کوئی
رخنہ نہیں بلکہ ایک اضافی خوبی ہے جو ایک وقت تک قرآن کریم کی حفاظت اور اس
کی تعلیم کی اشاعت کے لیے عمومی طور
پر استعمال میں لائی گئی اور جب اس کی افادیت سے زیادہ اس کا نقصان محسوس ہونے لگا تو اسے خوبی سے کام لینا چھوڑ دیا
گیا.اہل علم اور محققین خواہ وہ کسی مذہب یا عقیدہ سے تعلق رکھتے ہیں اس بارہ میں کسی قسم کے شک وشبہ میں مبتلا نہیں.چنانچہ ایک مستشرق John Burton قراءت کے حوالہ سے مفصل بحث کے بعد اپنی تحقیق کے آخر پر لکھتا ہے:
"No major differences of doctrines can be constructed
on the basis of the parallel readings based on the
Uthmanic consonantal outline, yet ascribed to mushafs
other than his.All the rival readings unquestionably
represent one and the same text.They are substantially
agreed in what they transmit..."1
(John Burton, The Collection of the Qur'an, Cambridge:
Cambridge University Press, 1977, p.171)
یعنی ( حضرت ) عثمان کے مصحف کے متوازی مختلف قراءتوں کے چلنے سے اعتقادی طور پر
کوئی بڑا اختلاف ممکن نہیں تھا اور تمام دوسری قراء تیں بلا شبہ ایک ہی متن کی نمائندگی کرتی
Page 316
الذكر المحفوظ
300
تھیں.یکمل طور پر ایک متفقہ مضمون آسے نقل کرتی تھیں.ویلیم میور کی یہ گواہی بہت سچی اور کھری ہے کہ:
No early or trustworthy traditions throw suspicion
upon Othman of tempering with the Coran in order to
support his own claim.......At the time of the recension,
there were still multitudes alive who had the Coran, as
Both of these sources
originally delivered, by heart;
must have proved an effectual check upon any attempt
of suppression.......(W Muir, The Life Of Mohammad, 1912, Edinburgh Pg: 558-559)
کسی بھی پرانی اور معتبر روایت سے ذرہ بھر شک کرنے کی وجہ پیدا نہیں ہوتی کہ حضرت عثمان
نے اپنے دعویٰ کی تائید میں قرآن شریف میں ایک ذرہ بھی تصرف کیا ہو....حضرت عثمان
کے تدوین قرآن کے وقت ابھی ہزارہا ایسے حفاظ صحابہ زندہ تھے جنہوں نے وقت نزول سے ہی
قرآن شریف کو سن کر حفظ کر لیا ہوا تھا....یہ دونوں ذرائع ایسی جسارت یا تصرف کو ثابت کرتے
اور مؤثر انداز میں اس کی روک تھام کرتے.اسی طرح کہتا ہے:
-
The recension of 'Uthman has been handed down to
us unaltered.So carefully, indeed, has it been preserved,
we might
that there are no variations of importance,
almost say no variations at all, - amongst the
innumerable copies of the Koran scattered through out
the vast bounds of empire of Islam.Contending and
embittered factions, taking their rise in the murder of
'Uthman himself within a quarter of a century from the
death of Muhammad have ever since rent the Muslim
world.Yet but ONE CORAN has always been current
amongst them....There is probably in the world no other
work which has remained twelve centuries with so pure
a text.(W Muir, The Lfe Of Mohammad, 1912, Edinburgh, John Grant,
pp.xxii-xxiii.)
حضرت عثمان کے عہد میں کی جانے والی تدوین ہم تک بلا رد و بدل پہنچی ہے.یقینی طور پر اتنی
احتیاط کے ساتھ محفوظ کی گئی ہے کہ تحریف کا کوئی امکان بھی نہیں ہے.ہم شائد حتمی طور پر یہ بھی کہہ
سکتے ہیں کہ وسیع اسلامی سلطنت کی حدود میں شائع بے شمار صحائف میں کوئی ادنی سی تبدیلی بھی نہیں
ہوئی.محمد (ﷺ) کی وفات سے لے کر عثمان (رضی اللہ عنہ ) کی شہادت تک عالم اسلام بہت
Page 317
قرآن کریم میں تحریف کے الزامات کے جواب
301
مشکل ادوار سے گزرا لیکن ہمیشہ مسلم دنیا میں ایک ہی قرآن رانج رہا...اس دنیا میں قرآن کریم کے علاوہ
اور کوئی کتاب ایسی نہیں جس کا متن بارہ صدیاں گزرنے کے بعد بھی اتنا محفوظ ہو جتنا قرآن کا ہے.یہ بھی بات ذہن میں رکھی جانے والی ہے کہ حضرت عثمان پر نام نہاد مسلمان مخالفین کی طرف سے بہت سے
مطاعن کیے جاتے رہے مگر اس دور میں جبکہ آپ تمام عرب کو قرآن کریم کی ایک قراءت پر اکٹھا کر رہے تھے تو
کسی عرب نے خواہ وہ مخالف تھا یا موافق آپ کے اس فعل پر یہ اعتراض نہیں کیا کہ قرآن کریم میں تحریف کی
جارہی ہے.قابل غور بات ہے کہ حضرت
علی بھی یہ گواہی دیتے ہیں کہ حضرت عثمان کا فعل جو صحابہ کے مشورہ اور
اتفاق رائے سے کیا گیا بہت صحیح تھا اور پھر حضرت علی سے جنگ کے وقت حضرت
امیر معاویہ کی طرف سے بھی
کبھی یہ اعتراض نہیں کیا گیا کہ آپ کے نزدیک وہ قرآن درست ہے جو باقی امت مسلمہ کے نزدیک قابلِ
اعتراض ہے.اور تو اور خارجی بھی اسی قرآن کو نیزوں پر بلند کر کے اس کے مطابق فیصلے کا مطالبہ کرتے.حضرت عثمان نے اپنے دور خلافت میں جب صحابہ کے اتفاق رائے سے یہ فیصلہ کیا کہ امت کو ایک قراءت پر
جمع کر دیا جائے اور یہ حکم جاری کیا کہ تمام عرب لغت قریش پر جمع کیسے اس قرآن کریم پر اکٹھا ہو جائے جو حضرت
ابو بکر کے دور خلافت میں صحابہ رسول کی نگرانی میں تیار کیے گئے نسخہ سے تیار کیا جارہا ہے اور باقی نسخے جلا دیے
جائیں.تو اس مرتبہ پھر حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو یہ حکم پسند نہیں آیا اور آپ نے اپنی پسند کی قراءت
والے اپنے صحیفہ کو محفوظ رکھنے کی کوشش کی جس میں آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریحی فرمودات بھی درج کیسے
ہوئے تھے جبکہ انہی وجوہ نزاع کو تو ختم کیا جارہا تھا لیکن کچھ عرصہ بعد آپ متفق ہو گئے.چنانچہ آپ فرماتے ہیں:
ان القرآن انزل على نبيكم من سبعة أبواب على سبعة احرف او حروف و
ان الكتاب قبلكم كان ينزل من باب واحد على حرف واحد معناهما واحد
ابن ابی داؤد: کتاب المصاحف الجزء الاول صفحه 18)
قرآن کریم تمہارے نبی (ع) پر سات دروازوں سے سات حروف پر نازل ہوا ہے.تم سے
پہلے کتابیں ایک ہی حرف پر نازل ہوتی تھیں.لیکن دونوں صورتوں میں معنی ایک ہی ہوتے ہیں.اس سے واضح ہوتا ہے کہ آپ کا اختلاف کوئی ایسا اختلاف نہیں تھا جس میں قرآن کریم کا مضمون یا آیات ہی
بدل جاتی تھیں.آپ صرف یہ فرماتے تھے کہ ایک علم جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے وہ کسی کے کہنے پر
کیونکر چھوڑ دیں؟ بہر حال جب آپ پر حکمت واضح ہوئی تو اپنے نسخہ کو تلف کر دیا اور پھر چوتھی بار قرآن کریم تحریر کیا
جو کہ لغت قریش کے مطابق تھا.یہ نسخہ آج بھی محفوظ ہے.(عبد الصمد صارم الازھری: تاریخ القرآن ، ایڈیشن 1985 ندیم
یونس پرنٹرز لا ہور ، پبلشرز: مکتبہ معین الادب اردو بازار لا ہور صفحہ 81)
یہ امر بھی قابل توجہ ہے کہ حضرت عثمان کے دور میں حضرت عبداللہ جیسا صاحب ایمان شخص جو اپنی قراءت کو
Page 318
الذكر المحفوظ
302
محض اس لیے نہیں چھوڑتا کہ یہ آپ نے حضرت رسول کریم سے سیکھی ہے کسی دوسرے کے کہنے پر کیوں چھوڑ دیں
کیسے ممکن ہے کہ وہ کسی ایسی بات پر راضی ہو جاتا جو حفاظت قرآن کے معاملہ میں درحقیقت شک پیدا کرتی ہو؟
جمع قرآن کے بارہ میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے خلافتِ راشدہ سے اختلافات پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوتا
ہے کہ خلافت راشدہ بہت غور و خوض کے بعد کسی حکمت کے تحت ایک حکم جاری کرتی تھی اور مستقبل میں سر اٹھانے
والے ممکنہ خطرات کو بھانپتے ہوئے حفاظت قرآن کے ضمن میں جو اقدام کیے، جیسے جیسے آپ پر ان اقدامات کی
حکمتیں کھلتی چلی گئیں آپ تسلیم کرتے چلے گئے.علاوہ ازیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر نگرانی دوسرے صحابہ کتابت قرآن
کا فریضہ سرانجام دے
رہے تھے اور پوری احتیاط برتی جارہی تھی تو اس کے مقابل پر ایک صحابی کے ذاتی اور نامکمل کام کو پیش کرنا
جو رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی خاص نگرانی میں بھی نہیں تھا، کس اہمیت کا حامل ہوسکتا ہے؟ ہمیں
حضرت ابن مسعودؓ کے کام کی اہمیت اور ان کی عظیم الشان خدمت قرآن سے انکار نہیں.مطلب صرف یہ ہے
کہ رسول
کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے زیر نگرانی اور باہتمام خاص ہونے والے کام کے مقابل پر ، اور صحابہ کے
متفقہ اور اجماعی فیصلہ کے برخلاف اس اختلاف کی کوئی اہمیت نہیں ہے.خصوصاً جبکہ عرب معاشرہ میں لکھنے کا
رواج نہیں تھا تو اس صورت میں ان مصاحف کا اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے زیر نگرانی تیار ہونے والے
مصاحف اور حفاظ کے حفظ کے مقابل پر کوئی فرق ہو تو اس کو اس کے سوا اور کیا حیثیت دی جاسکتی ہے کہ اسے ایک
ایسی غلطی سمجھا جائے جس پر ابتداء میں حضرت
عبداللہ بن مسعودؓ مصر تھے لیکن بعد میں اپنی غلطی کا اقرار کر لیا.مرکزی صحائف کے علاوہ تمام صحائف تلف کرنے کا حکم صحابہ کی متفقہ رائے اور اجماع سے کیا جارہا تھا.پس
اُس وقت صحابہ رسول کا ایک مرتبہ پھر متفق ہونا یہ بتاتا ہے کہ انہیں اطمینان تھا کہ آج اسی قرآن کریم پر امت کو
جمع کیا جارہا ہے جس پر حضرت ابو بکر کے دور میں امت پورے اطمینان سے جمع ہوئی تھی اور کسی قسم کی تحریف نہیں
ہورہی.نہ ہی اس دور کے اہل زبان مخالفین اسلام کی طرف سے یہ اعتراض ہوا کہ جس قرآن کی حفاظت کا
خدائی وعدہ تھا اس میں آج تحریف کی جارہی ہے.اس کی وجہ یہی تھی کہ صحابہ اور مخالفین دونوں گروہ پوری طرح
باخبر تھے اور جانتے تھے کہ یہ معاملہ تحریف کا نہیں بلکہ حفاظت کا ہے اور قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں کی جارہی.یہ بات بھی ذہن نشین رہنی چاہیے کہ اختلاف قراءت کے بارہ میں آج ہمارے پاس جو معلومات ہیں وہ بزبان
رواۃ سینہ بسینہ منتقل ہورتی رہیں اور حضرت عثمان کی اس خدمت کے اتنی یا سو سال یا اس سے بھی بعد تحریری صورت
میں اکٹھی کی گئیں ہیں.محققین نے تحقیق اور تدقیق سے اس ذخیرہ روایات میں مستند روایتوں کی کھوج کی.کچھ
لوگوں نے زیادہ سے زیادہ قراء توں کو کھوجنے کے شوق میں غلط روایات کو بھی اپنا لیا.آج اختلاف قراءت کے بارہ
میں مستند روایات کے مطالعہ سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے قرآن کریم بلا رد و بدل ہم تک پہنچا ہے اور غیر مستند روایات
Page 319
قرآن کریم میں تحریف کے الزامات کے جواب
303
جن پر بددیانت مخالفین اسلام اپنی تحقیق کی بنیا درکھتے ہیں قابل اعتنا نہیں ہوسکتیں.لطف یہ کہ ان غیر مستند روایات
سے بھی یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ قرآن کریم میں کوئی تحریف ہوئی ہے.یہاں یہ سوال اُٹھ سکتا ہے کہ مختلف قراء تیں حفص اور ورش وغیرہ تو اب بھی جاری ہیں.پھر حضرت عثمان نے کون
سا اختلاف ختم کیا.تو اس ضمن میں عرض ہے کہ علم القراءت ایک بہت وسیع علم ہے.اس میں باعث اختلاف حصہ
کو ختم کر کے قبیلہ قریش کی لغت پر اکٹھا کیا گیا.ورش کی موجودگی محافظت قرآن کے مخالف نہیں اور اتنی ضروری بھی نہیں.آج تلاوت قرآن میں لحن اور لہجہ کا فرق پایا جاتا ہے.اسے بھی اگر قراءت ہی کا فرق سمجھا جائے تو اس فرق
کو ختم نہیں کیا گیا اور نہ ہی ختم کرنے کی ضرورت تھی کیونکہ اس کی موجودگی اختلافات کا سبب نہیں ہے.آنحضور
صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا واضح ارشاد تھا کہ قرآن کو عربوں کے انداز میں پڑھو اور عربوں کے اختلاف لغت کے
علاوہ ہر قبیلہ کا اپنا لہجہ اور پڑھنے کا اپنا انداز تھا.پس وہ لہجے اور انداز آگے بڑھے.لغت کے اختلاف کا ذکر آج
صرف کتب میں پایا جاتا ہے اور ان لغات کے مطابق قرآن شائع نہیں کیے جاتے بلکہ مصحف عثمانی کے مطابق
شائع کیے جاتے ہیں اور قرآن کریم کی لغت کا جو اختلاف تھا وہ اب صرف اس کے اخذ معارف و معانی میں بطور
دلیل کے استعمال کیا جاتا ہے.پس آج جو اختلاف قراءت موجود ہے وہ لغت اور مختلف قبائل میں استعمال ہونے
والے مختلف مگر ہم معنی الفاظ کا اختلاف نہیں ہے بلکہ اس کی نوعیت دوسری ہے.وہ لحن اور حسن تلاوت وغیرہ سے
تعلق رکھتا ہے اور اس کی بنیاد بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی راہنمائی پر ہی ہے چنانچہ روایات ملتی ہیں:
عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَأَلْتُ اَنَسًا عَنْ قِرَاءَةِ النَّبِيِّ
ﷺ فَقَالَ : كَانَ يَمُدُّ مَدًّا.(سنن ابی داود کتاب الوتر باب استحباب الترتيل في القراءة)
حضرت قتادہ سے روایت ہے کہ میں نے انس سے نبی صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی قراءت کے
متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ والہ وسلم ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کیا کرتے تھے.عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم
يَقْطَعُ قِرَاءَ تَهُ يَقُولُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ - ثُمَّ يَقِفُ ثُمَّ يَقُوْلُ الرَّحْمَنِ
الرَّحِيمِ ثُمَّ يَقِفُ
(رواه الترمذى بحواله مشكاة المصابيح كتاب فضائل القرآن حدیث نمبر ٢٢٠٥)
ام المومنین حضرت اُم سلمہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
قرآن کریم کی تلاوت ٹھہر ٹھہر کر کرتے تھے آپ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِین پڑھ کر تو قف
فرماتے پھر الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ پڑھتے اور توقف فرماتے.عَن يَعْلَى فِي مَمْلَكِ أَنَّهُ سَأَلَ أَمْ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنْ قِرَاءَ وَ النَّبِيِّ
Page 320
الذكر المحفوظ
304
صلى الله عليه وسلم فَإِذَا هِيَ تَنْعُتُ قِرَاءَةً مُفَسِّرَةً حَرْفًا حَرْفًا.(رواه الترمذى وابوداود والنسائى بحواله مشكاة المصابيح كتاب فضائل القرآن)
يَعْلى بن سَمْلِكُ روایت کرتے ہیں کہ میں نے اُم المومنین حضرت اُم سلمہ رضی اللہ
عنہا سے آنحضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے قرآن کی تلاوت کے بارہ میں دریافت کیا تو انہوں
نے کہا کہ آنحضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی قراءت، قراءت مفسرہ ہوتی تھی یعنی ایک ایک حرف
کے پڑھنے کی سننے والے کو سمجھ آ رہی ہوتی تھی.یہ تو نمونہ کے طور پر چند روایات درج کی ہیں.ورنہ بہت کثرت سے روایات ملتی ہیں جن کے مطالعہ سے معلوم ہوتا
ہے کہ آنحضور نے تلاوت قرآن کے ضمن میں اپنے اقوال اور سنت کے نور سے امت کی بہت تفصیل سے راہنمائی فرمائی.اس بارہ میں ہدایات اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور رہنمائی کو بنیاد بناتے ہوئے قراءت کی یہ شکل ایک
با قاعدہ علم کی صورت میں آگے بڑھی.امت مسلمہ میں اس پر بہت کام ہوا اور ہر دور میں اس علم کے ماہرین موجود رہے ہیں.علم قراءت ایک وسیع علم ہے اور علماء اسلام نے اس پہلو سے اسے دیکھا کہ جیسے کلام اللہ اپنی جلالت سے انتہائی
عظمت لیے ہوئے ہے اسی طرح کلمات اللہ کی وہی عظمت اور شان ہے.پس دیگر تمام قرآنی علوم وفنون کی طرح یہ
علم وفن بھی کچھ کم عظمت کا حامل نہیں ہے اس لیے اس فن میں ابتدا سے ہی عربی میں بہت سی کتب لکھی جاتی رہیں اور
اس کے بھی ائمہ ہوئے.چنانچہ علامہ دانی اور علامہ شاطبی مشہور ائمہ ہیں.اس علم کو با قاعدہ سائنس کے طور پر آگے
بڑھایا گیا.علوم قراءت پر ایک نظر اس نہج سے بھی ڈالنی چاہیے کہ اتنے وسیع علم کی بنیاد جوڈالی گئی اور باقاعدہ سائنس
کی شکل دی گئی تو اس معاملہ میں گہری تحقیقات سے مسلمان علماء نے کیا نتیجہ نکالا؟ آیا یہ سب علوم سیہ ثابت کرتے ہیں
کہ قرآن کریم میں تبدیلی ہوئی ہے یا علماء اسلام اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ سب قرآن کریم کی حفاظت اور اس کی
اشاعت کا ایک بے نظیر انتظام تھا جو اور کسی کتاب کے لیے نہیں کیا گیا.اگران علوم سے یہ نتیجہ نکلتا کہ قرآن کریم میں
تبدیلی ہوگئی ہے تو پھر ان علما کا جودُنیا کے مختلف علاقوں میں بستے اور ایک دوسرے کے اثرات سے بالکل آزادان
علوم پر تحقیقات کرتے رہے، اسلام پر قائم رہنا اور مجموعی طور پر قرآن کریم کو غیر مبدل کلام الہی تسلیم کرنا اور اس یقین
پر قائم رہنا کیسے ممکن ہے؟ علاوہ ازیں یہ بھی چاہیے تھا کہ ان علوم سے امت مسلمہ کو دور رکھا جائے.لیکن معاملہ اس
کے برعکس ہے اور آج قرآنی علوم میں علوم قراءت پر سب سے زیادہ توجہ دی جاتی ہے.اگر اس علم سے قرآن کریم کی
حفاظت پر سوال اُٹھتے تو کیوں اسلامی دنیا میں سب سے زیادہ اس کو اہمیت دی جاتی ؟ اور کیوں ان علوم کے حصول
کے بعد لوگ سوال نہیں اُٹھاتے.مگر ہم دیکھتے ہیں کہ ان علوم میں خصوصی مہارت رکھنے والے قرآن کریم کے محفوظ
ہونے پر اسی طرح ایمان رکھتے ہیں جس طرح دوسرے مسلمان.اب ذرا ایک اور نمونہ ملاحظہ ہو کہ مستشرقین کس طرح دجل اور فریب کی راہ سے شکوک پیدا کرنے کی کوشش
Page 321
305
قرآن کریم میں تحریف کے الزامات کے جواب
کرتے ہیں.ابن وراق کہتا ہے:
Uthman`s codex was supposed to standardize the
consonantal text; yet we find that many of the variant
traditions of this consonantal text survived well into the
fourth Islamic century.The problem was aggravated by
the fact the consonantal text was unpointed, that isto
say, the dots that distinguis, for example, a "b" from a "t"
or a "th" were missing.Several other letters (f and q; j,h,
and kh; s and d; and z; s and sh; d and dh; t and z) were
indistinguishable.As a result, a great many variant
readings were possible according to the way the text was
pointed (had dots added).The vowels presented an even
worse problem.Originally, the Arabs had no signs for
the short vowels these were only introduced at a later
date.The Arabic script is consonantal.Although the
short vowels aresometimes omitted, they can be
represented by orthographical signs placed above or
below the letters -- three signs in all, taking the form of a
slightly slanting dash or a comma.---
After having settled the consonants, Muslims still had
to decide what vowels to employ: suing different
vowels, of course, rendered different readings.(Ibn Warraq: Why I am Not A Muslim, Prometheus Books, New
York, 1995, under heading; The Koran: Pg (109)
ابن وراق کہتا ہے: حضرت عثمان کے صحیفے کو ابتدائی ملتے جلتے منوں میں مرکزی حیثیت دی
گئی.پھر بھی ہمیں یہ روایات ملتی ہیں کہ بہت سے ملتے جلتے صحیفے چوتھی صدی ہجری تک محفوظ
رہے.مگر یہ مشکل مزید گھناؤنی شکل اختیار کر جاتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ متن بے نقط تھا.یعنی حروف پر نقاط نہیں تھے.مثلا حرف ”ب“ کو حرف’ت‘ سے جدا کرنے اور حرف ”ت“ کو
حرف ث سے جدا کرنے والے نقطے نہیں تھے.بہت سے دوسرے الفاظ ( ”ف“ اور ق؛
”ج“، ”ح“ اور ”خ“، ”و“ اور ” ” اور ” ، ”س“ اور ”ش“، ”و“ اور
اور ظ) میں امتیاز کرنا ناممکن تھا.اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب نقطے لگائے گئے تو
بہت سی قراء تیں ممکن تھیں.پھر vowels کے معاملے میں زیادہ مشکل پیش آئی.دراصل عربی
میں چھوٹے vowels کے لیے کوئی علامات تھیں ہی نہیں.یہ بعد میں ہی متعارف کروائے
گئے.عربی تحریر متشابہ ہے.اگر چہ کئی vowels حذف کر دیے گئے مگر ان کی جگہ حرکات لگائی
جاسکتی ہیں جو حروف کے اوپر یا نیچے ہوتی ہیں.یہ علامات ترچھی چھوٹی سی لکیر یا کومے کی شکل کی
9966.99
Page 322
الذكر المحفوظ
306
ہوتی ہیں.الفاظ کو منتخب کرنے کے بعد بھی مسلمانوں کو ابھی vowels لگانے تھے اور مختلف
vowels سے یقیناً مختلف قراء تیں بن جانی تھیں.اس جگہ بھی حسب معمول اعتراض کا کوئی موقع نہیں ملتا.اس لیے اعتراض بنانے کے لیے اپنا اکلوتا ہتھیار یعنی
دجل استعمال کرتا ہے اور یہ تاثر دینے کی کوشش کرتا ہے کہ گویا اختلاف قراءت کی وجہ اعراب اور نکتے بنے حالانکہ
حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے.اعراب اور نقاط 40 ہجری کی دہائی میں لگنے شروع ہوئے.اختلاف قراءت
آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی پہلی مرتبہ نظر آیا تھا اور آپ نے ہی اس کا فیصلہ بھی فرما دیا تھا اور اس فیصلے کو
بنیاد بناتے ہوئے حضرت عثمان نے 40 ھجری سے قبل ہی امت مسلمہ کو ایک مرکزی قراءت پر جمع کر کے اس
اختلاف کو ختم کر دیا تھا.پس یہ کہنا کہ اختلاف قراءت کی وجہ اعراب اور نقطے تھے اس پنجابی کہاوت کی یاد دلاتا ہے کہ:
ماں جمی نہیں ؛ تے پت بنیرے تے
یعنی ابھی والدہ پیدا نہیں ہوئی اور اس کی طرف منسوب کر کے ایک بیٹا پیش کیا جا رہا ہے.اعراب اور نقطے
وغیرہ اختلاف قراءت کے حل کے بہت بعد قریباً 40 ھجری کی دہائی میں بننے شروع ہوئے ہیں اور پھر ان کا
ارتقاء ہوا ہے.پہلے اعراب لگائے گئے ہیں اور پھر اس کے بعد حروف کے نقطوں کی باری آئی ہے.پس یہ کہنا کہ
اعراب لگانے سے اختلاف قراءت ہوا ہے ایک واضح دجل ہے.ہاں اعراب لگانے سے غیر عرب مسلمانوں
کے لیے عربی تحریر کا سمجھنا اور اختلاف قراءت کی حقیقت سمجھنا اور فرق کرنا آسان ہو گیا ہے.نیز یہ ذکر گز را که حضرت عثمان نے جو صحیفہ تیار کروایا اس میں اس بات کا خاص خیال رکھا گیا کہ جہاں تک ممکن ہو
لفظ اس طرح تحریر کیا جائے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ قراء تیں سموئی جائیں.اب علما تفسیری نکتہ نظر سے اخذ معارف
اور فہم قرآن کے لیے دیگر قراء توں کو بھی زیر بحث لاتے ہیں لیکن مرکزی متن اور مرکزی قراءت ایک ہی ہے.دوسرا دجل یہ کر رہا ہے کہ یہ تاثر دے رہا ہے کہ جس طرح انگریزی زبان میں vowels اگر نہ لگائے جائیں تو
لفظ مکمل نہیں ہوتا اسی طرح عربی میں بھی vowels ابھی لگا کر لفظ مکمل کرنا باقی تھا.حالانکہ درحقیقت عربی زبان
میں ایسی کوئی مشکل نہیں ہے.عربی میں اعراب لفظ کے اندر نہیں لگائے جاتے.بلکہ علامات کی شکل میں حرف
سے باہر لگائے جاتے ہیں اور ایسا زیادہ تر غیر عربی لوگوں کی آسانی کے لیے کیا جاتا ہے.اہل زبان عربوں کے
لیے بغیر اعراب کے عربی پڑھنا چنداں مشکل نہیں ہے.آجکل بھی عربی زبان کے چھپنے والے رسائل اور کتب
میں اعراب نہیں لگائے جاتے.قرآن کریم میں خاص طور پر اس لیے یہ خیال رکھا جاتا ہے کہ قرآن کریم ساری
دُنیا میں عربی زبان سے واقف یا نا واقف ہر مسلمان نے پڑھنا ہوتا ہے.پس اعراب کی وجہ سے ساری دُنیا میں
غیر عرب بچہ بھی آسانی سے قرآن کریم کی درست اور صحیح تلاوت کرتا ہے.اسی طرح یہ کہنا کہ حروف پر نقطے نہیں ہوتے تھے اس لیے اختلاف قراءت ہوا ، غلط ہے.ایک جیسے حروف
Page 323
قرآن کریم میں تحریف کے الزامات کے جواب
6699
6699
307
جیسے ” اور ”و “ اور ”“، ”س“ اور ”ش“ وغیرہ کی طرز تحریر میں فرق تھا جس کو عرب بخوبی پہچانتے
تھے اور پڑھنے والے بالکل صحیح پڑھتے تھے.نیز کثرت تلاوت اور حفاظ کی کثرت کی وجہ سے غلطی کا راہ پا جانا غیر ممکن تھا.سوال یہ ہے کہ جب اس بات پر اتنی واضح اور قطعی شہادتیں اور تاریخی دلائل موجود ہیں کہ قرآن کریم وہ واحد
مذہبی کتاب ہے جو ساتھ ساتھ ضبط تحریر میں آتی گئی ، حفظ کی جاتی رہی اور جس نبی پر نازل ہوئی اسی کی نگرانی میں
یہ سب کام سرانجام دیا گیا تو پھر تو کیوں ابن وراق نے یہ کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی زندگی میں
قرآن کریم تحریری صورت میں محفوظ نہیں تھا اور یہ کہ آپ کی وفات کے بعد صحابہ کو قرآن کریم جمع کرنے کی فکر
ہوئی اور مختلف لوگوں نے اپنی اپنی تحقیق کے مطابق مختلف آیات اکٹھی کر لیں.پھر اب قراءت کے معاملہ میں
دھوکہ دہی کی کوشش کیوں کی ؟ کیا ابن وراق جھوٹ بول رہا ہے اور دھوکہ اور فریب کی راہ سے حقیقت پر پردہ ڈال
رہا ہے؟ یا ابن وراق
کو واقعی صحیح اسلامی تاریخ کا علم نہیں ؟
لا زماً ابن وراق جھوٹ بول رہا ہے اور دھوکہ اور فریب کی راہ اختیار کر رہا ہے.کیوں کہ ابن وراق کو تاریخ کا
علم ہے اور کتاب میں اسلامی تاریخ پر مختلف مستند اور غیر مستند دونوں قسم کی کتب کے حوالے سے بات کرتا ہے.ہاں اُن میں موجود حقائق کو بگاڑ کر پیش کرتا ہے کیونکہ جانتا ہے کہ اس کا جھوٹ عام قاری نہیں پکڑ سکے گا اور یہی
سوچے گا کہ مسلمان علماء خود کو سچا کہتے رہتے ہیں اور غیر مسلم خود کو.حقیقت نہ جانے کیا ہے.اگر مان بھی لیا جائے کہ بفرض محال ابن وراق کو تاریخ کا علم نہیں ہے.تو پھر ہر شخص سوچ لے کہ بنا علم کے
کیوں اعتراضات کی بوچھاڑ کر دی اور کیوں مستشرقین کی کتب سے صرف اعتراضات ہی بچنے اور ان کے وہ
اعترافات نہیں چنے جو انہوں نے قرآن کریم کی حفاظت کے بے نظیر ہونے کے بارہ میں کیے.پس اگر علم نہیں تو
پھر بھی حق کی جستجو کرنے والے کسی شخص کے لیے قابل اعتبار ہی نہ رہا.قراءتوں کے حوالے سے ایک اور اعتراض ہے ابن وراق کو.کہتا ہے:
At present in modern Islam, two versions seem to be
in use: that of Asim of Kufa through Hafs, which was
given a kind of official seal of approvel by being adopted
in the Egyptian edition of the Koran in 1924; and that of
Nafi through Warsh, which is used in parts of Africa
other than Egypt.(Ibn Warraq: Why I am Not A Muslim, Prometheus Books, New
York, 1995, under heading; The Koran: Pg: 110)
موجود دور میں مسلمانوں میں دو قسم کے قرآن رائج ہیں.ایک حفص کے ذریعے ملنے والا
عاصم کوفی کا جسکو مصری حکومت نے 1924 میں اختیار کر کے ایک قسم کی سرکاری مہر اس کے استناد
پر لگادی ہے اور دوسرانافی کا جو ورش سے ملا ہے.جو کہ سوائے مصر کے باقی افریقہ میں رائج ہے.
Page 324
الذكر المحفوظ
308
جو شخص بھی ابن وراق کی کتاب کا مطالعہ کرے گا.اگر وہ اسلامی تاریخ سے واقف ہے تو اس کے اس طرح
بار بار دھوکہ دینے پر حیران ضرور ہو گا.آخر اتنا جھوٹ بولنے کی ضرورت اسی وقت ہی پیش آتی ہے جب اختلاف
کی کوئی بچی بنیاد نہ ملے.جب تمام معاملات واضح ہوں اور حقیقت کا علم ہو، پھر اگر حقیقت کو چھپانا ہوتو جھوٹ کا
ہی سہارا لینا پڑتا ہے.چنانچہ دجل اور فریب کے نمونے بار بار نظر آئیں گے.جہاں تک ابن وراق
کا یہ کہنا ہے کہ آجکل امت مسلمہ میں دو مختلف قسم کا قرآن کریم رائج ہے تو اس فرق یا
اختلاف کی نوعیت یہ ہے کہ پارے کہاں سے شروع ہوتے اور کہاں پر ختم ہوتے ہیں.نیز یہ فرق رکوعوں کی تقسیم
میں بھی ہے.پاروں
کی تقسیم تو صحابہ نے کی ہے اور رکوعوں کی تقسیم بہت بعد میں کی گئی.اسی طرح آیات میں
رموز و اوقاف کا فرق ہے جو کہ مختلف علماء نے بہت بعد میں لگائے ہیں تا کہ عربی سے ناواقف انسان تلاوت کے
وقت غلطی نہ کرے.پس یہ کوئی اختلاف نہیں بلکہ ایک معنوی وسعت ہے.چنانچہ اس حوالہ سے علماء نے بھی
ہت بحثیں کی ہیں اور قرآن کریم کی آیات کے اندر بھی مختلف ٹکڑوں کو مختلف انداز میں لے کر ان سے معانی
اخذ کیے ہیں.مثلا املاء ما من بہ الرحمن ایک مشہور کتاب ہے جس میں گرائمر کے لحاظ سے قرآن کریم کے معانی
اور معارف کو سمجھنے کی کوشش کی گئی ہے.اس کتاب میں بار ہا ایسی مثالیں ملیں گی جس میں آیات کے اندر مختلف الفاظ
کی مختلف تراکیب کر کے معارف اخذ کیے گئے ہیں.اسی طرح کشاف اور دیگر کتب تفسیر میں علمی نکات و معارف
اخذ کیے گئے ہیں.کچھ تراکیب رسول کریم صلی اللہ علیہ کی طرف منسوب ہیں اور کچھ علماء کی طرف.بہت
مغربی محققین اور مستشرقین بھی اس حقیقت کو سمجھتے ہیں.چنانچہ ایک مستشرق لکھتا ہے:
The simple fact is that none of the differences,
whether vocal or graphic, between the transmission of
Hafs and the transmission of Warsh has any great effect
on the meaning.Many are the differences which do not
change the meaning at all, and the rest are differences
with an effect on the meaning in the immediate context
of the text itself, but without any significant wider
influence on Muslim thought.(Andrew Rippin (Ed.), Approaches Of The History of
Interpretation Of The Qur'an, 1988, Clarendon Press, Oxford, p 37)
عام فہم حقیقت یہی ہے کہ حفص اور ورش کی قراء توں میں کوئی معنوی اختلاف نہیں ہے.جو
فرق ہیں وہ معنوی بالکل نہیں ہیں.اور جہاں لفظ کے معنوں میں فرق ہو بھی تو آیت کا مجموعی
معنی وہ فرق ختم کر دیتا ہے.لیکن یہ بھی کوئی خاص فرق نہیں ہے جو مسلمانوں میں کوئی اعتقادی
اختلاف پیدا کرے.
Page 325
قرآن کریم میں تحریف کے الزامات کے جواب
309
جب حضرت عثمان نے ایک قراءت پر لوگوں کو اکٹھا کیا تو اس کے بعد اختلاف قراءت بجائے جھگڑے کے
علم بن کرا بھرا اور دوسری صدی سے لے کر نویں صدی تک خوب پھیلا.علماء نے اس پر بہت سی کتب
لکھیں جن
میں تقریباً تمام معروف قراء توں کو درج کر لیا گیا اور باقاعدہ اس علم میں تحقیقات کے نئے نئے دروازے کھلے.پھر
ان میں سے آہستہ آہستہ مشہور اور مستند اور عمدہ قراء توں کو زیادہ اہمیت دی جانے لگی اور آہستہ آہستہ غیر معروف
قراء تیں کتابوں تک محدود ہوکر رہ گئیں اور نسبتا معروف قراء تیں آگے منتقل ہوتی رہیں.ابن مجاہد نے نویں صدی میں
ایک کتاب القرءات السبع لکھی جس میں ان سات
قراء توں پر تفصیلی بحث کی جو کہ زیادہ معروف تھیں.وہ قراء تیں یہ ہیں:
قاری نام را وی اول نام قاری دوم
نمبر شمار جگہ جہاں کی قراءت ہے
1
2
3
4
5
6
7
مد بینه
امام نافع
قانون
ورش
مکه
امام ابن کثیر
بردی
قنبل
بصره
امام ابو عمرو
دورى
سوسی
مشق
ابن عامر
ہشام
ابن ذکوان
کوفه
امام عاصم
شعبه
حفص
کوفه
21
امام حمزه
خلف
کوفه
امام کیساتی ابو الحارث
خلاد
دورى
یہ بڑی بڑی اور مشہور عام قراء تیں ہیں اور سب سے زیادہ استناد اور تواتر سے ہم تک پہنچیں.ان میں سے نمبر ایک اور نمبر پانچ سب سے زیادہ مشہور ہیں.پہلی قراءت جو کہ ورش کہلاتی ہے مصر کے علاوہ
سارے براعظم افریقہ میں پڑھی جاتی ہے اور پانچویں نمبر کی قراءت جو کہ حفص کے نام سے مشہور ہے باقی
اسلامی دنیا میں رائج ہے.ان میں سے حفص کے نام سے مشہور قراءت قریش کے مطابق ہے جبکہ ورش مختلف ہے.ابن وراق پاروں یا اجزاء کی تقسیم کے اختلاف اور آیات کے شمار کے اختلاف کو ورش اور حفص کی تفریق سے خلط ملط کر
کے یہ تاثر دینے کی کوشش کرتا ہے کہ گویا قرآن ہی دو مختلف قسم کے بنے ہوئے ہیں.یہ اعتراض فی ذاتہ اپنے غلط ہونے کی شہادت رکھتا ہے.اہل اسلام میں اگر مختلف قرآن رائج ہوتے تو لازماً
اس کا ذکر عام ہونا چاہیے تھا.کسی بھی علاقہ سے چھپنے والے نسخہ قرآن میں اگر کوئی غلطی راہ پا جائے تو شور مچ جاتا
ہے اور اغلاط نامے وغیرہ شائع ہوتے ہیں.دوسرے فرقوں کے ملا غلطی کرنے والوں کے خلاف کفر کے فتاویٰ
شائع کر دیتے ہیں.مگر یہ دو قرآن ایسے ہیں کہ ان کے تضاد کی مسلمان علماء سے پہلے ہی ابن وراق
کو خبر پہنچ گئی.پھر دیانت دار اہل علم محققین اور مستشرقین بھی ان دونوں قرآنوں سے ناواقف رہے.ویلیم میور بھی یہی کہتا رہا
کہ ONE CORAN has always been current دوسرے مذاہب کے متعصب ملا اور خاص کر
Page 326
الذكر المحفوظ
310
عیسائی پادری اور مستشرقین اعتراض کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے اور جہاں حفاظت قرآن کے موضوع
کو لے کر بے بس ہو جاتے ہیں تو پھر جھوٹ پر جھوٹ بولتے ہیں.اتنی کثرت سے جھوٹ کی نجاست پر منہ
مارنے کی ضرورت ہی کیا ہے.بس دونوں قرآن پیش کر دیا کریں.ایک تحقیق
گزشتہ صدی میں میونخ یونیورسٹی کے شعبہ The Institute for Koranforschung نے قرآن کریم
کے چوبیس ہزار سے زائد قدیم مکمل اور نامکمل نسخے ساری دُنیا سے اکٹھے کیے تھے.جو کہ قرآن کریم کے قدیم
ترین نسخہ کی نقل سے لے کر اس دور تک ہر صدی میں اور ہر زمانہ میں پائے جانے والے نسخوں پر مشتمل تھے.ان
نسخوں پر قریباً 50 سال کی گہری تحقیق کے بعد محققین نے متفقہ طور پر یہ نتیجہ نکالا کہ تحریر کی معمولی غلطیوں کے علاوہ
ان تمام قرآنی نسخوں میں آپس میں کوئی ادنی سا بھی اختلاف نہیں ہے.افسوس کہ یہ یونیورسٹی دوسری جنگ عظیم
کے دوران بمبار منٹ سے تباہ کر دی گئی مگر پیچھے یہ نہایت عمدہ تحقیق اپنی یادگار چھوڑ گئی.محمد حمید اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم ادارہ اسلامیات لاہور، صفحہ 179)-1
2- (Method of preservations of the Quran during the Prophet's
time
(http://www.islam101.com/quran/source_quran.html)
کاش ابن وراق سے پہلے کوئی اس حقیقت کو پالیتا اور افریقہ کے اس دوسرے قرآن کا کوئی نسخہ جرمنی بھجوا
دیتا.کم از کم یونیورسٹی والے اپنی 50 سالہ تحقیقات کا نتیجہ تو غلط نہ نکالتے.اب تک ابنِ وراق نے دجل اور تلیس کی راہ سے تاریخ کو مسخ کر کے اعتراضات بنانے کی کوشش کی ہے.ان سب اعتراضات کے بعد اب ابنِ وراق یہ تکلیف بھی اُٹھانے کے لیے تیار نہیں کہ تاریخی حقائق کو توڑ موڑ کر
پیش کرے بلکہ اب تعصب اور بغض میں حد سے گزرتے ہوئے محض اپنے اندازوں اور قیاس کے سہارے ایسے
لچر اور بیہودہ اعتراض کرنے پر اتر آیا ہے جن کا نہ کوئی سر ہے اور نہ کوئی پیر.اگر قاری اپنی نا واقفی اور سادگی کی وجہ
سے ابنِ وراق کے تمام تر دھوکوں اور فریب کو حقیقت سمجھ بیٹھا ہے اور اس بات کا قائل ہو گیا ہے کہ تاریخی اعتبار
سے قرآن کریم کی حفاظت مشکوک ہے تو اب یہ موقع ہے کہ اب اسی بنیاد پر اعتراضات پیش کیے جائیں.چنانچہ
آئندہ سطور میں ابنِ وراق کہ اعتراضوں کی نوعیت علمی اور تاریخی نہیں بلکہ محض ظنی ہے.اب قاری کچھ ایسے
اعتراضات کا سامنا کرے گا کہ قرآن کریم کا فلاں لفظ الہامی نہیں ہوسکتا.فلاں مضمون ایسا ہے کہ خدا تعالی بیان
نہیں کرسکتا.سورتوں کی آیات کا سٹائل ایسا ہے جو بتاتا ہے کہ یہ آیات بعد میں ڈالی گئی ہیں.وغیرہ وغیرہ.
Page 327
حفاظت قرآن کریم پر متفرق اعتراضات
311
متفرق اعتراضات
قرآن کریم میں استعمال ہونے والے لفظ ”قل“ پر اعتراض
As
many
have pointed out, one only need to add the
imerative "say" at the beginning of the sura to remove
the difficulty.This imperative from the word "say"
ocares some 350 times in the Koran, and it is obvious
that this word has, in fact, been inserted by later
compilers of the Koran, to remove countless similarly
embarrassing difficulties.Ibn Msood, one of the
companions of the Prophet and an authority on the
Koran, rejected the Fatihah and surah 113 and 114 that
contain the words, "I seek refuge" as not part of the
Koran.Again at sora 6.104 the speaker of the line "I am
not your keeper" is clearly Muhammad....these words
are unworthy of God:"
(Ibn Warraq: Why I am Not A Muslim, Prometheus Books, New
York, 1995, under heading; The Koran: Pg: 106)
جیسا کہ بہت سے لوگوں نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ کسی بھی سورت کے شروع میں لفظ
قل“ کا اضافہ در پیش مشکلات کو دور کرنے کے لیے کیا جاتا ہے.قل“ کا یہ حکمیہ انداز
قرآن کریم میں 350 مرتبہ اپنایا گیا ہے.در حقیقت بہت سی معنوی مشکلات سے جان چھڑانے
کے لیے یہ لفظ قرآن کریم کو جمع اور مدون کرنے والوں نے بعد میں اپنی طرف سے شامل کر دیا
ہے.چنانچہ قرآن کریم پر سند مانے جانے والے صحابی رسول، ابنِ مسعودسورۃ الفاتحہ، 113 اور
114 ( سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو جو قل“ کے الفاظ سے شروع ہوتی ہیں متن قرآن کا
حصہ نہ مانتے تھے.نیز چھٹی سورت کی آیت نمبر 104 (الانعام : 105 - مترجم ) میں "وَمَا أَنَا
عَلَيْكُم بِحَفِيظ “ کے الفاظ سے محمد ( ﷺ ) خود مراد ہیں.قرآن کریم کے یہ حصے خدا
تعالیٰ کے شایانِ شان نہیں.اس شبہ کے جواب میں ہمارا سوال یہ ہے کہ ایسا کب ہوا ؟ گزشتہ صفحات میں تفصیل کے ساتھ یہ ثابت کیا گیا ہے
کہ قرآن کریم کی حفاظت کا نظام ایسا تھا کہ کوئی اس میں رد و بدل نہیں کر سکتا تھا اور نزول قرآن اور جمع و تدوین قرآن
کے دور میں دوستوں اور دشمنوں کی خاموشی اس حقیقت پر گواہ ہے نیز ہر دور میں اہل علم بلاتمیز مذہب وعقیدہ اس
Page 328
الذكر المحفوظ
312
بارہ میں گواہی دیتے چلے آئے ہیں کہ قرآن میں کوئی رد و بدل نہیں ہوا.اب ابنِ وراق کو یہ اعتراض ہے کہ قرآن
کریم میں کئی آیات سے پہلے لفظ فال آیا ہے جو ثابت کرتا ہے کہ یہ آیات الحاقی ہیں.ہمارا سوال یہ ہے کہ یہ کس
طرح ثابت ہو گیا ؟ تاریخ تو یہ بتاتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ لفظ اسی طرح متن قرآن کا
حصہ تھا جس طرح آج ہے.صحیح بخاری میں حضرت عائشہ کی روایت ہے:
عن
عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذ اوى لى فراشه كل
ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ
الْفَلَقِ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ
(بخاری کتاب تفسیر القرآن باب فضل المعوذتين)
رسول کریم رات بستر پر لیٹتے تو ہمیشہ اپنی ہتھیلیوں پر قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ اور قُلْ أَعُوذُ
بِرَبِّ الْفَلَقِ اور قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ پڑھ کر پھونکا کرتے.اسی طرح ایک دوسری روایت میں ہے:
حضرت عائشہ فرماتی ہیں ؛ جب رسول اللہ بیمار ہوتے تو آپ اپنے جسم پر معوذات پڑھ
پڑھ کر پھو لکھنے اور اگر شدت بیماری سے آپ کو توفیق نہ ہوتی تو میں ایسا کیا کرتی تھی.اسی طرح روایت ملتی ہے کہ:
(بخاری کتاب تفسیر القرآن باب فضل المعوذتين
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جريف عن بيان عن قيس بن ابی حازم عن
عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم الم تر آيات
أنزلت الليلة لم يُر مثلهن قط قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ
(صحيح مسلم كتاب صلاة المسافرين و قصرها باب فضل قرائة المعوذتين)
یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تجھے علم ہے کہ آج رات ایسی آیات نازل ہوئی ہیں
کہ ان جیسی پہلے کبھی نہیں دیکھی گئیں یعنی قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ اور قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ
مذکورہ بالا روایات کے علاوہ بھی کثرت سے مستند روایات ملتی ہیں کہ یہ آیات رسول کریم کے دور میں وحی الہی
کے طور پر مشہور اور معلوم تھیں اور ان کے شروع میں لفظ قل “ آتا تھا.اس سے ظاہر ہوتا ہے رسول کریم صلی اللہ
علیہ والہ وسلم کے دور میں آپ اور آپ کے صحابہ لفظ ” قل “ کو اسی طرح وحی الہی اور متن قرآن
کا جز وسمجھتے تھے
جس طرح کوئی بھی دوسرا قر آنی لفظ وحی الہی اور جز سمجھا جاتا تھا.پس جب یہ لفظ رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم
کے دور میں بھی قرآن کریم کے متن میں موجود تھا اور صحابہ کو اور اس دور میں عربی جاننے والے مخالفین کو یہ
Page 329
حفاظت قرآن کریم پر متفرق اعتراضات
اعتراض نہ ہوا تو اب کیا اعتراض ہے؟
313
لفظ ”قل “ کا استعمال تو بذات خود آنحضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی صداقت کی ایک بہت بڑی دلیل اور
حفاظت قرآن کریم کا ایک اعلیٰ ثبوت ہے.اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم پر جو بھی
وحی الہی نازل ہوتی تھی آپ اُسے بعینہ آگے پہنچا دیتے تھے اور اپنی سوچ سے کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کیا کرتے
تھے.بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ حکم رسول کریم کو دیا جارہا ہے کہ آگے بنی نوع سے کہہ دے اور آپ اس حکم کے
الفاظ بھی بعینہ بیان کر دیتے ہیں کہ ایسا کہا گیا ہے کہ قل أعوذ...اب اگر کسی کو یہ کہا جائے کہ لوگوں سے کہہ
دو کہ کھانا کھا لیں تو وہ جا کر یہ اعلان تو نہیں کرتا کہ لوگوں سے کہہ دو کہ کھانا کھا لیں وہ تو یہی کہے گا کہ لوگوکھانا
کھائو مگر رسول کریم بعینہ الفاظ دہرا دیا کرتے تھے.اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خواہ کوئی لفظ آپ کی ذات
سے متعلق ہی کیوں نہ ہوتا اور جیسا بھی ہوتا آپ اسے بعینہ آگے پہنچانا اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے.اور
کبھی کوئی لفظ
یہ سوچ کر نہیں چھوڑتے تھے کہ یہ تو آپ کی ذات کے حوالہ سے بات ہو رہی ہے یا اس لفظ کے مخاطب صرف آپ
ہیں باقی امت نہیں.پس ” قل “ کی موجودگی جائے اعتراض نہیں بلکہ حفاظت قرآن کریم کے حوالہ سے آنحضور
کی بیمثال دیانتداری کا بہت اعلیٰ ثبوت ہے.سوال یہ ہے کہ کوئی مثال، کوئی ثبوت تو دو کہ جس سے علم ہو کہ یہ لفظ کب اور کس نے ڈالا تھا؟ ہاں ایک مثال
پیش کرتا ہے مگر پیش کر کے اپنے پاؤں پر خود ہی کلہاڑی مار لیتا ہے.دعویٰ یہ ہے کہ یہ لفظ قرآن کریم مدون کرنے
والوں بعد میں نے ڈالا ہے اور مثال ابن مسعود کی پیش کر رہا ہے جو اُن صحابہ میں سے تھے جنہوں نے رسول کریم
صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے دور میں ہی قرآن کریم کا ایک بڑا حصہ تحریر کیا تھا اور آپ نے بھی یہ سورتیں لکھی تھیں
لیکن بعد میں کسی وجہ سے اپنے صحائف سے مٹادیں.یہ اختلاف بتا تا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں
یہ لفظ اسی طرح قرآن کریم کا حصہ تھا جیسا کہ آج ہے.پھر روایات میں واضح ذکر ہے کہ اس بارہ میں رسول کریم
سے جب پوچھا گیا تو آپ نے بتایا کہ مجھے یہ سورتیں ایسے ہی سکھائی گئی ہیں اس لیے میں تو ایسے ہی تلاوت
کروں گا.پس جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دے رہے ہیں تو کیسے کہا جاسکتا ہے کہ بعد میں ڈالا گیا ؟
یعنی مدون کرنے والوں نے نہیں ڈالی یہ سورتیں بلکہ عبداللہ بن مسعودؓ نے رسول کریم کی وفات کے بعد اپنے صحیفہ
سے مٹادی تھیں.کیوں؟ اس بارہ میں ہم پہلے دیکھ آئے ہیں کہ حضرت ابن مسعود کوئی دلیل نہیں دیتے.نیز اس بات کا اعتراض سے کیا تعلق ہے کہ عبداللہ بن مسعود معوذتین کو قرآن کریم کا حصہ نہیں سمجھتے تھے؟ اگر
یہ مراد ہے کہ ابن مسعودؓ لفظ ” قل“ کی وجہ سے معوذتین کو نہیں مانتے تھے تو پھر چاہیے تھا کہ آپ ان تمام مقامات
کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیتے جہاں جہاں لفظ ”قل قرآنی آیات میں استعمال ہوا ہے.مگر ان تمام آیات کا
Page 330
الذكر المحفوظ
314
تسلیم کرنا اور صرف معوذتین کا انکار کرنا بتاتا ہے کہ وجہ لفظ ”قل نہیں کچھ اور تھی.حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے
مسئلہ پر بحث گزرچکی ہے.یہاں سر دست یہی بیان کرنا مقصود ہے کہ آپ لفظ ” قل “ کی وجہ سے قرآن کریم کی
کسی آیت کو رد نہیں کرتے کیونکہ بقول ابن وراق قل“ قرآن کریم میں 350 جگہ استعمال ہوا ہے اور سوائے
معوذتین کے ہر جگہ ابن مسعودؓ نے اسے متن قرآن کا حصہ سمجھا ہے.پھر یہ بھی مد نظر رہے کہ تاریخ اسلام میں کوئی
ایک بھی مثال
نہیں ملتی کہ لفظ ” قل “ کی وجہ سے صحابہ یا جید علماء نے قرآن کریم کی ثقاہت میں شک کیا ہو.پھر ابن وراق کی دلیل اس حقیقت کے واضح ہو جانے کے بعد تو بالکل ہی بے حقیقت جاتی ہے جب ہم دیکھتے
ہیں کہ ابن مسعودؓ نے اپنی غلطی سے رجوع کر لیا اور پہلے کی طرح معوذتین کو دوبارہ اپنے صحیفہ میں درج کر لیا تھا.گویا درج کر کے یہ بتا دیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ سورتیں درج کرتا تھا پھر بعد میں رائے بدل گئی
مگر وہ غلطی تھی.اب دوبارہ درج کرتا ہوں.اس طرح بزعم خودا بن وراق
کا اکلوتا گواہ بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے.مزید ملاحظہ ہو کہ اعتراض تو یہ ہے کہ قرآن کریم مدون کرنے والوں نے تحریف کر دی اور اس ضمن میں
دوسری دلیل کیا ہے؟ ابن وراق الانعام آیت : 105 کے حوالہ سے کہتا ہے ، یوسف علی اپنے ترجمہ میں اس جملے
کے شروع میں لفظ کہہ دے کا اضافہ کرتا ہے.جو کہ اصل عربی متن میں نہیں ہے اور ایسا بلا کسی وضاحت اور
حاشیہ کے کرتا ہے اس سلسلہ میں عرض ہے کہ جب تمہیں یہ تسلیم ہے کہ عربی متن میں یہ لفظ موجود نہیں ہے تو پھر
اس سے قرآن کریم کے محفوظ ہونے پر کیا اعتراض وارد ہوتا ہے؟ یوسف علی کا دفاع ہمارا مقصود نہیں.مگر کیا ابن وراق
کو یہ نہیں معلوم کہ قرآنی متن میں تحریف اس کے ترجمہ میں کسی لفظ کے زائد کرنے یا نکالنے سے ممکن نہیں؟ ہاں
اعتراض تو تم پر وارد ہوتا ہے کہ میاں عربی سیکھ کر قرآن کریم سمجھنے کی کوشش کرو.تراجم پڑھ پڑھ کر اعتراض نہ جمع
کرتے جاؤ.تم تو کہہ رہے ہو کہ بعد میں تدوین کرنے والوں نے یہ لفظ ڈال دیا اور مثال یوسف علی کی پیش
کر رہے ہو.کیا یوسف علی نے قرآن کریم مدون کیا تھا؟
سوال یہ ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے دور میں لفظ ”قل“ کا قرآنی وحی میں شامل ہونے کا
ذکر ملتا ہے اور آنحضور اسی طرح ان سورتوں اور آیات کو پڑھتے تھے.صحابہ کو بھی اس میں کوئی شک نہیں ہوا اور پھر
بعد میں عربی کے جید علماء کو بھی اس میں شک نہیں ہوا تو تمہیں اب کیا تکلیف ہے؟ خود ہی ابھی سیوطی کا حوالہ دے
کر آئے ہو کہ اس عظیم مفسر کو پانچ جگہ شک ہوا.اب بتاؤ کہ باقی 345 جگہ اس کی عظمت نے کیوں گواہی دی کہ ان
مقامات پر قل قرآن کریم کی وحی کا حصہ ہے؟ باقی یہ بھی دجل ہے کہ سیوطی کو 5 جگہوں پر شک ہوا ہے کہ یہ خدا تعالیٰ
کی وحی نہیں ہے.علامہ سیوطی تمام تر قرآن کریم کو حرف بحرف وحی الہی مانتے ہیں.پس سیوطی جیسا عالم ، جس کی
عظمت ابنِ وراق جیسے متعصب کو بھی مسلم وہ تو اعتراض نہیں کرتا اور ابنِ وراق عربی زبان اور اس کے باریکیوں
Page 331
حفاظت قرآن کریم بر متفرق اعتراضات
315
سے ناواقف اور نابلد ہو کر محض دوسروں کی دیکھا دیکھی اس معاملہ میں بھی زبان طعن دراز کر رہا ہے.علامہ سیوطی کہیں یہ نہیں کہتے کہ قرآن کریم میں کوئی ایک لفظ بھی ایسا ہے جو خدا تعالیٰ کا بیان فرمودہ نہیں بلکہ
انسانی ہے.قرآن کریم کے الہی کلام ہونے کے بارہ میں آپ کی ایک گواہی پہلے درج کی جاچکی ہے ایک یہ ہے کہ
اپنی مشہور کتاب، الاتقان، جس کا حوالہ ابن وراق دیتا ہے، کے تمہیدی نوٹ میں اس حقیقت کا اعتراف اور اپنے
ایمان
کا اظہار کرتے ہیں کہ قرآن کریم انسانی طاقتوں سے بالا ایک الہبی کلام ہے.آگے چلنے سے قبل ایک ذرہ پھہر کر غور
کر لیجئے کہ ابن وراق نے یہ جھوٹ کیوں بولا؟ شائد یہی وجہ ہے کہ کوئی بچی بنیاد تو کیا کوئی کمزوری دلیل بھی نہیں ملی
جو شبہ پیدا کر سکے کہ سورۃ الفاتحہ خدا تعالیٰ کا کلام نہیں ہے.اس لیے اس جھوٹ کو ہی اپنے اعتراض کی بنیاد بنارہا ہے.پس ”قل “ کے بارہ میں مستند روایات اور احادیث میں واضح طور پر مذکور ہے کہ رسول کریم کے دور میں اسی طرح
متن قرآن میں موجود تھا جس طرح آج ہے.تدوین قرآن کے دوران کب یہ تحریف ممکن ہوئی ؟ تمام تر ثبوتوں کو
پس پشت ڈالتے ہوئے محض اندازے لگانا کہ قل لاز مابعد میں ڈالا گیا ہوگا پرلے درجہ کی بیہودگی نہیں تو اور کیا ہے؟
باقی رہی حکمت کی بات تو لفظ ”قل ان جگہوں پر لایا گیا ہے جہاں مضمون کو خوب پھیلانے اور اس کی
اشاعت کی ضرورت ہوتی ہے.یوں تو تمام قرآن کریم کے بارہ میں بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ (المائده: 68)
کا ارشاد ہے یعنی جو تجھ پر نازل کیا گیا ہے اسے آگے پہنچا دے مگر بعض مضامین کے بارے میں بطور خاص
اعلان کرتے چلے جانے کا ارشاد ہے.چنانچہ انہی مضامین کے شروع میں ”قل “ کا لفظ آتا ہے.حضرت
خلیفہ اسیح الثانی فرماتے ہیں:
قل “ کا لفظ ان مضامین یا سورتوں سے پہلے آتا ہے جن کے اعلانِ عام کا ارشاد ہوتا ہے
اور یہ ظاہر ہے کہ کسی امر کا اعلانِ عام ایک آدمی نہیں کرسکتا.ایسے اعلان کا ذریعہ ایک جماعت
ہی ہوسکتی ہے.جو نسلاً بعد نسل یہ کام کرتی چلی جائے تا کہ ہر قوم و ملک کو بھی وہ پیغام پہنچ جائے
اور ہر نسل اور ہر زمانہ کے لوگوں کو بھی وہ پیغام پہنچ جائے.اگر وحی متلو میں یعنی قرآن میں قل کا
لفظ نہ رکھا جاتا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم تک یہ حکم چلتا.آپ کے بعد یہ حکم نہ چلتا.لیکن جبکہ قرآن کی وحی میں یہ لفظ شامل کر دیا گیا تو اب اس کے متواتر تا قیامت جاری رہنے کی
صورت پیدا ہو گئی.جب اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے فرمایا کہ قُلْ يَأَيُّهَا
الْكَافِرُونَ تُو کافروں کو مخاطب کر کے کہہ دے کہ اے کا فرو! میں تمہارے معبود کی عبادت قطعاً
نہیں کرتا اور نہیں کر سکتا.تو آپ نے یہ اعلان کا فروں میں کر دیا مگر قل کا لفظ پہلے نہ ہوتا تو
مسلمان سمجھتے یہ محمد رسول
اللہ کا کام تھا، ختم ہو گیا.لیکن جب آپ نے وحی مسلمانوں کو سنائی اور
Page 332
الذكر المحفوظ
316
یوں پڑھا قُلْ يَأَيُّهَا الْكَافِرُونَ تو ہر مسلمان نے سمجھ لیا کہ یہ حکم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
ذات کے لیے نہ تھا بلکہ میرے لیے بھی تھا کیونکہ میرے سامنے جب وحی محمد صلی اللہ علیہ وسلم
نے پڑھی ہے تو اس کے پہلے قبل کہا ہے جس کا مخاطب میں ہی ہوسکتا ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ
علیہ والہ وسلم نہیں کیونکہ وہ تو پڑھ رہے ہیں سُن تو میں رہا ہوں.پس اُس نے اس حکم کی تعمیل
میں یہ پیغام آگے پہنچا دیا لیکن چونکہ قُل کا لفظ وحی میں تھا اُس نے بھی اگلے شخص کے سامنے
اسی طرح پیغام پہنچا دیا کہ قُل لفظ بھی دُہرایا اور اُس تیسرے شخص کے سامنے جب قُل کا لفظ کہا
گیا تو اُس نے سمجھ لیا کہ صرف مجھے پیغام نہیں پہنچایا گیا بلکہ مجھ سے یہ بھی خواہش کی گئی ہے کہ
میں آگے دوسروں تک یہ پیغام پہنچا دوں.غرض اس طرح تا قیامت اس حکم کے دہرانے کا
انتظام کر دیا گیا ہے.جب عام قرآنی سورتوں کو انسان پڑھتا ہے تو اُسے وہ حکم پہنچ جاتا ہے جو
ان میں ہے مگر جب وہ اس سورت یا آیت کو پڑھتا ہے جس سے پہلے قُل لکھا ہو تو وہ سمجھ جاتا
ہے کہ اسے آگے پہنچاتے چلے جانا میر افرض ہے اور وہ خود عمل کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو
بھی عمل کی نصیحت کرتا ہے اور ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ تم یہ پیغام اپنے بعد کے لوگوں تک اور وہ
اپنے بعد کے لوگوں تک پہنچادیں.اب اس حکمت کو سمجھ لو کہ وہ لوگ کتنے دھو کے میں ہیں جو
کہتے ہیں کہ قل کا لفظ وحی میں کیوں رکھا گیا ہے.آج کل لوگ بے نام کا ر ڈ ڈال کر
بھجوا دیتے ہیں اور اُن میں لکھ دیتے ہیں کہ اس خط کا مضمون نقل کر کے دس اور آدمیوں کو بھجوا دو.کچھ لوگ اس پر
عمل کر کے دس اور کو وہ مضمون لکھ کر بھجوا دیتے ہیں اور سارے ملک میں وہ بات
پھیل جاتی ہے.آج کل بہت سی لغو باتوں کے متعلق یہ طریق اختیار کیا جاتا ہے مگر اشاعت کے
لیے یہ طریقہ بہت عمدہ ہے بعض قرآنی سورتوں یا آیتوں سے پہلے قُل کا لفظ رکھ کر قرآن نے بھی
یہی طریق اختیار کیا ہے اور گویا اس طریق کی ایجاد کا سہرا بھی قرآن کے سر ہے.( تفسیر کبیر جلد دہم صفحہ 405, 404 زیرتفسیر الکافرون آیت2)
پھر ابن وراق یہ بھی اعتراض کرتا ہے کہ فلاں فلاں آیات خدا کا کلام نہیں ہوسکتیں کیوں کہ اُن میں
رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم مخاطب کر رہے ہیں یا اس لیے خدا کا کلام نہیں ہوسکتیں کیونکہ ان کا سٹائل مختلف ہے
یا اس لیے خدا کا کلام نہیں ہوسکتیں کہ اُن کا مضمون یا انداز بیان ایسا ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں ہوسکتا.اس قسم کے اعتراضات اٹھانا ایک دھوکہ اور دجل ہے.ایک طرف مستند تاریخ ہے اور دوسری طرف
جھوٹ کی بنیاد پر گھڑے ہوئے اعتراضات کا پلندہ اور جہاں جھوٹ نہیں بولتا وہاں کوئی دلیل نہ ہونے کی وجہ
سے بیہودہ اندازے اور بے ثبوت تخمینے لگا نا شروع کر دیتا ہے.
Page 333
حفاظت قرآن کریم پر متفرق اعتراضات
317
ان مستشرقین کی یہ گری ہوئی اخلاقی حالت اور ادنی ادنی معاملات میں دجل اور فریب اور دھوکہ دینے کی
عادت بتاتی ہے کہ خدا تعالیٰ سے ان کا کوئی دُور کا بھی تعلق نہیں.یہ اعتراضات ان کے دماغ کی اختراع ہیں.نہ
تو یہ لوگ عربی زبان کے ایسے ماہر ہوتے ہیں کہ عربی اسالیب کو سمجھ سکیں ، نہ ہی ملہم من اللہ ہونے کے دعویدار ہیں
کہ خدا تعالیٰ کے کلام کے انداز سے واقفیت کا دعوی کر سکیں اور نہ ہی ان کی مسلّمہ کتب جن پر یہ ایمان کے دعویدار
ہیں اس درجہ استناد کو پہنچتی ہیں کہ ان کے بارہ میں یقین سے کہا جاسکے کہ اُن کے کثرتِ مطالعہ سے الہی کلام کے
اسلوب بیان کے فہم اور عرفان کا دعوی کیا جاسکتا ہے اور نہ ہی اسلام کے سوا کسی اور مذہب کی کتاب کا مطالعہ الہی کلام
کا عرفان پیدا کر سکتا ہے کیونکہ فی زمانہ اب یہ ناممکن ہو چکا ہے.وہ کتب بھی انسانی دست برد کا شکار ہو چکی ہیں.پس ایک سوال یہ بھی ہے کہ قطع نظر اس بات کے کہ حفاظت قرآن کے بارہ میں تاریخ کیا کہتی ہے، مغربی
محققین کو آیا یہ حق بھی پہنچتا ہے کہ وہ یہ بات کریں کہ فلاں فلاں آیت بعد میں ڈالی گئی ہے کیونکہ اس کا انداز باقی
سورۃ سے مختلف ہے یا اس کا ربط باقی سورۃ یا مضمون سے نہیں بنتا؟ کیا مستشرقین کو اتنی صلاحیت حاصل بھی ہے کہ
وہ عربی عبارتوں کو اس طرح سمجھ سکیں جس طرح کہ اہل زبان عربوں نے ان پر تحقیقات کی ہیں؟ مستشرقین کا
ایک استاد مارگولیتھ ، عربی کا پروفیسر ، اور بزعم خود عربی ” سٹائل کو سمجھنے والا عربی میں گفتگو کرنے کے چیلنج پر کچھ ہی
دیر میں عاجز آ گیا ( تفسیر کبیر جلد 10 صفحه 78 ز يرتفسیر القريش)
پس ایک طرف عربی زبان سے ناواقفیت اور دوسری طرف یہ کہنا کہ یہ کلام خدا کا نہیں محمد (ﷺ) کا ہے
کیونکہ اس کا انداز ایسا ہے جو خدا کا نہیں ہوسکتا، ایک لچر دعوئی اور محض تمسخر ہے کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے کلام سے واقفیت رکھنے والے جانتے ہیں کہ دونوں کلام ایک ہستی کے نہیں ہو سکتے.یہ بزعم خود سٹائل کے
ماسٹر اتنا بھی نہیں سمجھ سکے کہ قرآن مجید اور مجموعہ احادیث دو مختلف کلام ہیں جو ایک ہستی کی طرف منسوب نہیں
ہو سکتے.زبان عربی کے ماہر اور آسمان ادب عربی پر جگمگاتے ستارے بخن فہم اور اسلوب بیان کے شہسوار یہ گواہی
دے چکے ہیں کہ قرآن کریم کا انداز انسانی طاقت اور قدرت سے باہر ہے اور یہ کلام انسانی کلام ہو ہی نہیں سکتا
اور لازماً کلام الہی ہے.پس اگر تمہارا اسلوب درست تسلیم کرتے ہوئے محض قیاس اور اندازوں کی بنیاد پر قرآن
کریم کے انداز پر اعتراض کی بنیا د رکھی جائے تو ماننا پڑے گا کہ اُس دور میں جبکہ عربی ادب اپنی رفعتوں
کو چھورہا
تھا، مخالفین میں آسمان ادب کے درخشاں ستارے اور بڑے بڑے سحر بیان سخن ور موجود تھے وہ تو اپنی تمام تر
مہارتوں کے باوجود اس حقیقت کو نہ سمجھ سکے.مگر اسلوب ادب عربی سے ناواقف مستشرقین آج قرآن کریم کے
تراجم پڑھ پڑھ کر اس کے اسلوب کو نہ صرف سمجھ گئے بلکہ عربی ادب کی باریکیوں سے واقفیت بھی حاصل کر گئے.پس مستشرقین اس بات کے حق دار نہیں کہ اپنی جہالت
کو بنیاد بنا کر اندازوں اور قیاس کی بنیاد پر حقائق کو جھٹلا سکیں.
Page 334
الذكر المحفوظ
318
اس لیے ہم اس اعتراض کے جواب میں یہی سوال دہراتے ہیں کہ اگر تم سچ بول رہے ہو اور علی وجہ البصیرت بات
کر رہے ہو تو اس کا کیا ثبوت ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ یہ کلام میرا نہیں بلکہ خدا تعالیٰ
کا ہے اور ثبوت یہ ہے میں نے آج تک کسی ادنیٰ سے ادنی معاملہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولا.خدا پر کیسے بول سکتا
ہوں؟ اب جب ایک شخص کہتا ہے کہ یہ کلام میرا نہیں ہے بلکہ خدا کا ہے اور پھر کوئی دوسرا دعویدار بھی موجود نہیں کہ
یہ کلام اس کا ہے اور نہ ہی کبھی کسی نے کسی دوسرے شخص کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ کلام بناتے
ہوئے دیکھا ہے.رسول کریم کی طرز کلام بھی قرآن کریم کی طرز کلام سے بالکل مختلف ہے.پھر مقابلہ میں کلامِ الہی کی
مثل نہ لا سکنے کا چیلنج پندرہ سو سال سے مخالفین کامنہ کالا کر رہا ہے.پھر قرآن کریم ایسے مضامین پر مشتمل ہے جو
انسانی طاقت سے بالا ہیں، ایسی پیشگوئیاں ہیں جو صرف خدا کی طرف سے ہوسکتی ہیں اور ایسی تاثیر ہے جوصرف
البی کلام میں ہوسکتی ہے تو پھر لازماً اسے خدا تعالیٰ کا کلام ماننا پڑے گا اور اگر ایسا دعویٰ کرنے والے محمد الصدوق
الامین صلی اللہ علیہ والہ وسلم ہوں تو پھر قانون شہادت کی رو سے ما نالازم ہو جاتا ہے کہ یہ کلام خدا تعالیٰ کا ہی
ہے.مزید برآں یہ کہ تاریخی دلائل اور عقلی اور نفلی ثبوت تمام تر اسی بات پر متفق ہیں.اگر پھر بھی تسلیم نہیں تو
قرآن کریم بار بار فیصلہ کے لیے بلا تا ہے کہ مال بنا کر پیش کرتا
حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب خلیفہ اسیح الثانی اصلح الموعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں :
اعتراض کرنا سہل ترین کام ہے جو کوئی شخص اپنے مد مقابل کے خلاف کر سکتا ہے.صداقت
کے منکر ہمیشہ اعتراضوں تک ہی اپنے حملہ کو محدود رکھتے ہیں کبھی کوئی ٹھوس کام مقابل پر نہیں
کرتے جس سے ان کے جو ہر بھی ظاہر ہوں اور ان کے اعتراض کی حقیقت بھی ظاہر ہو.یہی
حال قرآن کریم کے منکروں کا تھا.وہ قرآن کریم پر اعتراض تو کرتے تھے لیکن اس کے مقابل پر
کوئی تعلیم ایسی پیش نہیں کرتے تھے جو اس سے برتر تو الگ رہی اس کے برابر بھی ہو.آج تک
قرآن کریم کے مخالفوں کا یہی حال رہا ہے.مسیحی مصنف قرآن کریم پر اعتراض کرتے چلے
66
جاتے ہیں لیکن آج تک اس مطالبہ کے پورا کرنے کی جرأت نہیں کر سکے.“
( تفسیر کبیر جلد اول صفحہ 226 زیرتفسير آيت البقرة: 25, 24، کالم :1)
ابن وراق کی حالت تو ایسی ہے جیسے کوئی شخص Colour Blind ہو ، اور کسی مصوّر کی شاہکار تصویر میں رنگوں
کی خوبصورت جلوہ گری نہ دیکھ سکے کیونکہ اپنی معذوری کی وجہ سے اسے تو وہ رنگ دھبے ہی نظر آتے ہیں.اس
میں مصور کا تو کوئی قصور نہیں.ایک آنکھوں والا تو رحیم ہی کھا سکتا ہے کہ یہ بے چارہ جلو ہ حسن کے نظارہ سے ہی محروم
ہے.پھر اگر کسی کو اُس ذات کامل کا حسن نظر نہ آئے تو اس کی بیچارگی کی کیا حد ہو سکتی ہے ! ہاں یہ چیلنج عام ہے کہ ساری
Page 335
حفاظت قرآن کریم پر متفرق اعتراضات
دنیا کے منکر مل کر اگر مثل بنا سکتے ہیں تو بنا کر دکھا ئیں.319
پس جن آیات کے بارہ میں بلا دلیل صرف یہ کہتا ہے کہ یہ الفاظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں تو اس کے جواب
میں ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ رسول کریم کا دعویٰ موجود ہے کہ یہ الفاظ خدا تعالیٰ کی طرف سے اُن پر نازل کیے گئے
ہیں.پس یہ الفاظ محمد صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے نہیں ہیں اور اس کے ثبوت میں گزشتہ صفحات میں دلائل درج کیسے
جاچکے ہیں کہ کوئی عقلی یا فقلی شہادت اس بات پر نہیں کہ یہ کلام رسول کریم کا ہے اللہ کا نہیں.مثلاً ابن وراق یہ
آیت پیش کرتا ہے وَمَا أَنَا عَلَيْكُمُ بِحَفِيظ ( سورۃ الانعام آیت 105 ) اور کہتا ہے کہ اس میں محمد (ﷺ)
مخاطب ہیں.ایک طرف رسول کریم فرماتے ہیں کہ یہ کلام میرا نہیں اور خدا تعالیٰ بھی یہ گواہی دیتا ہے کہ قرآن
کریم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی تبدیلی نہیں کی گئی اور دوسری طرف یہ انداز ملتا ہے اور عربی جاننے
والے اور عربی زبان کی باریکیوں سے واقف اور شعر پنشن میں کمال رکھنے والے ہمعصر مخالفین اعتراض نہیں کرتے
کہ یہ حصہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے ڈالا ہے کیونکہ اس میں بظاہر آپ مخاطب ہیں اور نہ ہی
آپ پر ایمان لانے والے اہل زبان یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ایک طرف تو خدا کا کلام ہونے کا دعوی ہے اور
دوسری طرف یہ انداز بیان؟ پس یہ تو کوئی دلیل نہیں کہ فلاں آیت میں رسول کریم مخاطب ہیں.کیونکہ صرف
قرآن مجید میں ہی نہیں بلکہ ساری دُنیا کے ادب پاروں میں بارہا یہ انداز اپنایا گیا ہے.پس ابن وراق کو یہ
خوبصورت رنگ بھی نظر نہیں آیا ، یا وہ اس حقیقت سے بھی اعراض کر گیا ہے کہ یہ ایک اعلیٰ درجہ کا ادبی انداز ہے.بہت سے ادبانے اس کی تقلید کی ہے اور بے شمار مثالیں ملتی ہیں کہ مصنف کسی خیالی کردار کی طرف سے بات کر رہا
ہوتا ہے بلکہ ایسی مثالیں بھی ملتی ہیں کہ مصنف ایسے کردار کی طرف سے بات کرتا ہے جو کہ حقیقی زندگی میں ہوتا ہی
نہیں یا اگر ہو بھی تو بے جان ہوتا ہے.اس لحاظ سے عام سی بات کو خوبصورت پیرائے میں جو کہ قاری کی دلچسپی کا
موجب ہوتا ہے بیان کیا جاتا ہے.قرآن کریم اس انداز کو اپناتا ہے اور بہت اعلیٰ انداز میں اپنا تا ہے.ایک
فرضی واقعہ یا صرف الفاظ کی تک بندی نہیں بلکہ ایک حقیقت بیان کرتا ہے.علاوہ ازیں اس بیان میں اور بھی بہت سی حکمتیں پوشیدہ ہیں.مثلاً یہ کہ اس انداز بیان کو اپناتے ہوئے کلام
کے تحت السطور اللہ تعالیٰ مخالفین کو یہ مضمون بھی سمجھاتا ہے کہ اس رسول (ﷺ) کا اس کلام کہنے والے سے ایک
قریبی تعلق ہے اور اس کا اظہار یہ ہے کہ خدا تعالیٰ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی طرف اس انداز میں
جواب دیتا ہے کہ گویا آپ مخالفین سے گفتگو کر رہے ہیں.اس طرح خدا تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی
زبان اور اپنی زبان کو گویا ایک ہی قرار دے رہا ہے.یہ تو انتہائی قربت اور پیار کا لطیف اظہار ہے.کہیں اللہ تعالیٰ
محبت اور پیار کے اس تعلق کو اپنے اور محمد صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے آپس کے تعلق کے حوالہ سے انتہائی محبت کے
الله
Page 336
الذكر المحفوظ
320
ساتھ جمالی انداز میں لطیف پیرایہ میں بیان کرتا ہے اور کہیں مخالفین کے شور وشر پر انتہائی جلال کے ساتھ بیان
کرتا ہے.مثلاً ایک جگہ فرماتا ہے:
إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ الله طَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمُ (الفتح: 11)
جولوگ تیری بیعت کرتے ہیں وہ صرف اللہ کی بیعت کرتے ہیں.اللہ کا ہاتھ ان کے
ہاتھوں پر ہے.ایک دوسری جگہ جلالی رنگ میں اس قربت کا اظہار کرتے ہوئے فرماتا ہے:
وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى (الانفال : 18)
اور جب تو نے پتھر پھینکے تھے تو تو نے نہیں پھینکے تھے بلکہ اللہ نے پھینکے تھے..گرد و پایش موجود سب صحابہ اور مخالفین جانتے تھے کہ آپ کی نے روت رضوان لی تھی اور آپ ہی نے بدر
کے موقع پر کفار کی طرف کنکر پھینکے تھے.عام ادبی تحریر میں جب کوئی مصنف کسی فرضی کردار کی بابت ایسا رویہ
اپنا تا ہے تو ہرگز اس کی مراد کوئی حقیقت بیان کرنا نہیں ہوتی بلکہ صرف ایک ادبی انداز کی تقلید کرتا ہے جو کہ ایک
خوبصورت انداز ہے بلکہ بعض دفعہ تو اس خوبصورتی کو اپناتے ہوئے حقیقت سے بھی دور چلا جاتا ہے.مثلاً جب
کوئی مصنف کسی بے جان کردار کی زبان میں بات کرتا ہے تو کیا پڑھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ وہ بے جان چیز سے اپنی
محبت کا اظہار کر رہا ہے یا بے جان چیز اس کے اس انداز سے واقعۂ بولنے لگے گی.صرف ایک انداز ہے جو
پڑھنے والوں کو اچھا لگتا ہے.قرآن کریم کی اضافی خوبی یہ ہے کہ اس انداز کو اس طرح اختیار کرتا ہے کہ مضامین
میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے.اسی طرح قرآن
کریم انبیاء کے مخالفین کے اقوال بھی بیان کرتا ہے.اب کیا ابن وراق کی موٹی عقل یہ فتویٰ
دے گی کہ جہاں فرعون کا قول بیان کیا ہے وہاں خدا تعالیٰ نہیں بلکہ فرعون نے قرآن کے نزول سے چودہ صدیاں
پہلے یہ آیت قرآن کریم میں داخل کر دی تھی ؟ یا جہاں انبیاء کے اقوال کا حوالہ دیا ہے وہاں انبیاء نے خود اپنی
طرف سے قرآن کریم میں وہ آیت داخل کر دی ہے؟ پس یہ حسن کلام کا ایک شہرکار نمونہ ہے نہ کہ جائے اعتراض.قاری دیکھ لے کہ قرآن کریم کے انداز پر اعتراض کرنے والا یہ معترض ” ابن وراق“ اس معروف ادبی انداز
کو بھی نہیں سمجھ سکا.قرآن کا سٹائل کیا سمجھے گا.
Page 337
حفاظت قرآن کریم پر متفرق اعتراضات
321
اعتراض محققین کے مطابق قرآن کریم کی بہت سی آیات الحاقی ہیں
ابن وراق حسب معمول قرآن کریم کی حفاظت کے لیے اختیار کیے گئے تمام تر اقدامات کو نظر انداز کرتے
ہوئے کہتا ہے کہ:
The authenticity of many verses has also been called
into question not only by modern Western scholars, but
even by Muslims themselves.Many Kharijites, who
were followers of Ali in the early history of Islam, found
the sura recounting the stroy of Joseph offensive, an
erotic tale that did not belong in the Koran.بہت سے جدید مغربی مستشرقین نے ہی نہیں بلکہ بہت سے مسلمانوں نے بھی اکثر آیات
کے استناد پر سوال اُٹھایا ہے.بہت سے خارجی ، جو کہ اسلام کی ابتدائی دور میں (حضرت) علی
کے پیروکار تھے، ان کے لیے سورت یوسف ناراضگی کا موجب ہے کیونکہ وہ جذبات کو انگیخت
کرنے والی ایک ایسی کہانی ہے جو قرآن سے تعلق نہیں رکھتی.اسی طرح کہتا ہے :
Shiites, of course, claim that Uthman left out a great
many verses favorable of Ali for political reasons.(Ibn Warraq: Why I am Not A Muslim, Prometheus Books, New
York, 1995, under heading; The Koran: Pg: 112)
یقیناً اہل تشیع کا بھی دعویٰ ہے کہ (حضرت) عثمان نے بہت سی ایسی آیات محض سیاسی
وجوہات کی بنا پر درج نہیں کیں جو کہ (حضرت) علی کی مؤید تھیں.ہم ابنِ وراق سے پوچھتے ہیں کہ اگر تمہیں مغربی محققین اور خارجیوں سے ایسے قوی دلائل مل ہی گئے تھے تو
اُن دلائل کو چھپا کے کیوں رکھ لیا؟ اگر دلائل موجود تھے تو پھر جھوٹ اور فریب کی نجاست پر منہ کیوں مارا؟ علمی
بحث اپنی جگہ لیکن حقائق سے واقف قاری کے دل میں یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ اگر واقعی اتنے قوی دلائل میسر
تھے تو کیوں دجل اور تلمیس کی راہ اختیار کر کے خود کو غیر معتبر بنالیا ؟ بجائے اس کے کہ اُن مسلمان محققین کے
دلائل پیش کرتے تم نے جھوٹ کا زہر کھایا اور علامہ سیوطی کے بارہ میں خلاف واقعہ بات لکھی.اگر یہ مسلمان اور
غیر
مسلم محققین تمہاری امداد کے لیے موجود تھے تو کیوں انہیں پیش نہ کیا اور کیوں علامہ سیوطی کے بارہ میں جھوٹ
بولا؟ پس ہم یہ نتیجہ نکالنے میں حق بجانب ہیں کہ تمہیں کہیں سے دلیل نہیں ملی اسی لیے تمہیں جھوٹ کا سہارا لینا پڑا
Page 338
322
الذكر المحفوظ
اور تبھی تو یہ اعتراض اُٹھاتے ہوئے بھی کوئی دلیل پیش نہ کی.جہاں تک مغربی محققین کا چند آیات پر قلم اٹھانے کا سوال ہے اس بارہ میں عرض ہے کہ مغربی مستشرقین نے ہی
قرآن کریم کی حفاظت پر بھی گواہیاں بھی دی ہیں کہ یہ راست راست بلاکم وکاست آج تک محفوظ ہے.ان گواہیوں کا
ذکر گزشتہ سطور میں بھی آتا رہا ہے اور آئندہ بھی آتا رہے گا.پس سوال یہ ہے کہ جن محققین نے چند آیات کے استناد پر
سوال اُٹھایا ہے وہ اپنے اس دعوی کی صداقت کا ثبوت کیا دیتے ہیں؟ کسی کی محض ہرزہ سرائی تو قابل توجہ نہیں ہوسکتی.ان نام نہاد محققین نے ایک زمانہ تک محض تنگ نظری، تعصب اور اسلام دشمنی کو بنیاد بناتے ہوئے اسلام
اور بانی اسلام پر گندے اور گھناؤنے اور بلا دلیل و ثبوت اعتراضات کی بوچھاڑ جاری رکھی.ان کی مت اس
قدر ماری گئی کہ اس حقیقت کو کلیۂ فراموش کر بیٹھے کہ حقائق اور زمان و مکاں ان کے گھٹیا اور لچر تصورات کے
پابند نہیں.چنانچہ جوں جوں یورپ جہالت کے اندھیروں سے باہر نکلنا شروع ہوا توں توں مستشرقین کے
سنجیدہ طبقہ کے حقیقت پسندانہ مطالعہ نے رفتہ رفتہ ان لغویات کو مستر د کرنا شروع کیا.آہستہ آہستہ اور گھٹے گھٹے
انداز میں یہ لوگ کبھی کبھی پادریوں اور نام نہاد مستشرق محققین کے دجل وفریب کا ذکر بھی کر دیتے اور اس رویہ
پر ندامت کا اظہار اور معذرت خواہانہ رویہ اختیار کر لیتے.پھر ان میں کچھ ایسے لوگ سامنے آئے جنہوں نے
کھلم کھلا کہنا شروع کیا کہ مغربی محقق تعصب اور اسلام دشمنی میں علمی تحقیق کے نام پر دلوں کی کی سیاہی سے جو
صفحات کالے کرتے رہے ہیں اور جس قبیح اور شرمناک علمی اور تاریخی بددیانتی کے مرتکب ہوتے رہے ہیں یہ
اب ان کے گلے کو طوق بن چکا ہے اور ہمیشہ ” مہذب مغرب کے لیے باعث عار اور باعث شرم رہے گا.اس
کا یہ مطلب نہیں کہ یہ لوگ اسلام کی اعلیٰ تعلیمات کے قائل تھے.ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ ننگے اور عریاں
جھوٹ سے پر ہیز کیا جائے اور اسلامی تعلیم کا مطالعہ کر کے اس کا مقابلہ کیا جائے نہ کہ اپنے دماغ کے گند سے
نت نئے فلسفے اور قصے تخلیق کر کے اسلام کی طرف منسوب کیے جائیں.چنانچہ علمی تحقیق کے نام پر ان مستشرقین
نے بھی اسی روایتی تعصب سے خوب کھل کر کام لیا.ابن وراق کے مددگار نام نہاد متقین کے بارہ میں تو خود مغرب کے دیانت دار محقق کہتے ہیں کہ محض اسلام
دشمنی اور تعصب میں اسلام اور بانی اسلام اور قرآن کریم کی طرف ایسی باتیں منسوب کرتے ہیں جن کا حقائق
سے کوئی دُور کا بھی تعلق نہیں ہوتا.کیرم آرمسٹرانگ جیفری لینگ اور ایڈور ڈھیڈ کی تحقیق کا ذکر اس ضمن میں گزرا.ٹامس کارلائل کی گواہی بھی سُن لیجیے :
Our current hypothesis about Mahomet, that he was a
scheming Imposter, a Falsehood incarnate, that his
religion is a mere mass of quackery and fatuity, begins
really to be now untenable to any one.The lies, which
Page 339
323
حفاظت قرآن کریم بر متفرق اعتراضات
well-meaning zeal has heaped around this man, are
disgraceful to ourselves only.(Thomas Carlyle: On Heroes, Hero-Worship and the Heroic in
History, p.41)
صلى الله
ہمارا یہ تصور اب کسی کے لیے بھی قابل قبول نہیں رہا کہ نبی عربی ( نعوذ باللہ ) ایک
عوکہ دینے والے شخص تھے، اُن کا ذہن خرامات کا مجموعہ تھا.عمد جانتے بوجھتے ہوئے ان کے خلاف
جو کذب وافترا کا طوفان بدتمیزی برپا کیا گیا ہے یہ صرف ہماری ہی ذلت کا موجب ہوا ہے.اور اس رویہ کی مذمت کرنے والوں کی یہ فہرست چھوٹی نہیں ہے.بہت سے دیانت دار اہل علم جیسے
جارج برناڈشا، جان لین پورٹ، سٹینلے لین پول، ڈاکٹر ہنری اسٹب ، گاڈفرے، اور بہت سے محققین جنہیں تمام
دنیا عظیم تسلیم کرتی ہے، کھل کر یہ کہتے ہیں کہ مغربی محققین کا محض کہانیاں بیان
کردینا تو معتبر نہیں ہوسکتا.اس لیے
جب تک کوئی دلیل پیش نہ کی جائے ایسے لچر اعتراضات قابل اعتنا نہیں ہو سکتے.بلکہ یہ تو عیسائیت اور
اہل مغرب کے لیے باعث ذلت ہیں.اب ابن وراق نے مغرب کا یہ ننگ دوبارہ اُچھال دیا ہے.اہل مغرب کو
آستین کے اس سانپ پر اور اس قماش کے دوسرے نام نہاد محققین پر نظر رکھنی چاہیئے.تاریخی اور نقلی دلائل کے بارہ میں عام طور پر مستشرقین اختلاف کرنے کی زیادہ جرات نہیں کرتے یا اگر کرتے
ہیں تو ابن وراق والا ہتھیار استعمال کرتے ہیں ؛ یعنی دجل اور فریب.ایک اور عجیب وطیرہ یہ بھی ہے مستشرقین کا
کہ عربی زبان کے علم میں کورے ہونے کے باوجود کہتے ہیں کہ اس آیت کا سٹائل ایسا ہے کہ یہ اس سورۃ کی نہیں لگتی
یا یہ کہ اس کا سٹائل بتاتا ہے کہ یہ آیت بعد میں شامل کی گئی ہے.چونکہ ابن وراق نے مستشرقین کے حوالہ سے یہ ذکر نہیں کیا
کہ اُن کے پاس اس دعوئی کا ثبوت کیا ہے اس لیے ہم انہیں جوابات پر اکتفا کرتے ہیں جو گزشتہ میں درج ہو چکے.جہان تک ابن وراق کے اس قول کا تعلق ہے کہ مسلمانوں نے خود اس بارہ میں شک کا اظہار کیا ہے کہ بعض
آیات قرآن کریم کا حصہ نہیں ہیں اور پھر اپنی بات کو سچا کرنے کے لیے کہتا ہے کہ حضرت علی کے پیرو کار خارجیوں
نے سورۃ یوسف پر اعتراض کیا ہے کہ یہ سورت کلام الہی کا حصہ نہیں ہوسکتی.اس کے جواب میں ہم اتنا ہی کہتے ہیں کہ سورۃ یوسف مکی دور میں نازل ہوئی اور کبھی کسی مخالف نے یہ
اعتراض نہ کیا کہ ایک طرف تو ہماری اخلاقی حالتوں پر ہمیں ملزم ٹھہراتے ہو اور ہماری اصلاح کا دعویٰ لے کر
سامنے آئے ہو اور دوسری طرف ایسی اخلاق باختہ سورت پیش کرتے ہو؟ حضرت ابوبکر کے دورِ خلافت میں
جمع قرآن کے وقت کسی نے اعتراض نہ کیا اور تمام امت نے متفقہ طور پر گواہی دی کہ موجودہ صورت میں
قرآن کریم کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جو کلام الہی کا حصہ نہ ہو اور انتہائی اعلیٰ درجہ کا استناد اپنے اندر نہ رکھتا ہو.پھر
اس گواہی کے ساتھ اکٹھا کیا ہوا قرآن کریم کا نسخہ حضرت علیؓ کے دورِ خلافت میں بھی موجود تھا.یہ نسخہ اور قرآن کریم
Page 340
الذكر المحفوظ
324
کے وہ نسخے جو کہ حضرت عثمان نے حضرت ابوبکر کے نسخے سے نقل کروائے تھے ان سب پر حضرت علیؓ نے
خوشنودی کا اظہار فرمایا تھا.نہج البلاغہ میں درج آپ کے 127 نمبر خطبہ میں تو آپ یہاں تک فرماتے ہیں کہ
عثمان نے جو کام کیا ہے وہ اگر نہ کرتے تو یہی خدمت میں سرانجام دیتا.آپ اپنے دور خلافت میں اسی قرآن کریم کو
استعمال کرتے رہے.پس جب اس درجہ استناد کے ساتھ قرآن کریم محفوظ کیا گیا اور حضرت علی بھی اسے ہی استعمال
کرتے رہے تو خارجیوں کے ہاتھ ایسی کون سی دلیل لگ گئی جو انہوں نے اعتراض کر دیا؟ خارجیوں کے سردار (بقول
ابن وراق نعوذ بالله من هذه الخرافات) تو قرآن کریم کے استناد کو تسلیم کرتے ہیں کہ وہ رسول کریم سے لے کر اب تک
محفوظ ہے اور آپ کو سورۃ یوسف پر بھی کوئی اعتراض نہیں تو پھر خارجیوں کو کیا اعتراض ہے؟ پھر حیرت کی بات ہے کہ
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور آپ کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر کے جمع قرآن کے دور میں اور پھر
حضرت عثمان کے عہد خلافت میں تو سورۃ یوسف پر نہ مسلمانوں کی طرف سے کوئی اعتراض ہوتا ہے اورنہ مخالفوں کی طرف سے
لیکن حضرت علی کے دور میں جبکہ مسلمانوں کے خلاف سیاسی محاذ آرائیاں اپنے عروج پر تھیں یہ اعتراض اٹھایا جاتا ہے.پس خارجیوں نے سورت یوسف کے کلامِ الہی نہ ہونے کی کیا دلیل دی ؟ کیا وہ خود ملہم من اللہ ہونے کے
دعویدار تھے اور خدا تعالیٰ نے انہیں بتایا تھا کہ یہ سورت قرآن کریم کا حصہ نہیں بلکہ بعد میں ڈالی گئی ہے یا انہوں
نے اس سورت کے الحاقی ہونے کے بارہ میں کوئی ثبوت پیش کیا تھا؟
ابن وراق کا یہ کہنا بھی ایک خلاف حقیقت بات ہے کہ خارجی حضرت علیؓ کے ابتدائی دور کے پیروکار تھے.خارجیوں پر بحث کا موقع نہیں مختصر بیان کرنا ہی مناسب ہے کہ اگر اس دور کے حالات کا مطالعہ کریں تو معلوم
ہوتا ہے کہ خارجی وہ سیاسی لوگ تھے جن کے خاص عزائم تھے جیسے خلافتِ راشدہ کو اور اسلامی مرکزیت کو ختم کرنا
اور اسلامی اتحاد کو پارہ پارہ کرنا اور وہ ان عزائم کو پورا کرنے کے لیے مذہب کا غلط طور پر استعمال کرتے تھے.ان
کا سرغنہ عبداللہ بن سبا ایک بہت ذہین اور با صلاحیت یہودی تھا اور اس نے جرائم پیشہ لوگ اکٹھے کر لیے تھے اور
کچھ سادہ لوح مسلمانوں کو بھی دھوکہ اور فریب کی راہ سے ورغلا کر اپنے ساتھ شامل کر لیا تھا.یہ مسلمان زیادہ تر
عدم تربیت یافتہ نو مبایعین تھے جو مرکز سے دُور رہتے تھے اور مرکز سے رابطہ نہ رکھنے یا مذہب میں زیادہ دلچسپی
نہ ہونے کی وجہ سے اسلامی تعلیمات سے بے بہرہ تھے لیکن چونکہ تھے مسلمان اس لیے عبداللہ بن سبا اُن کو حضرت علی
کے حوالہ سے دھوکہ دیتا تھا کہ حضرت علی خط لکھ لکھ کر عبد اللہ بن سبا کی رہنمائی کر رہے ہیں اور حضرت عثمان کے
ظلم و ستم سے پریشان ہیں.ساتھ ہی اس ڈر سے کہ حضرت علی کو علم ہو گیا تو اس کی خیر نہیں ، وہ عیارا انسان یہ بھی
کہتا کہ ان خطوط کے مضمون کو راز ہی رکھو ورنہ (حضرت) عثمان (رضی اللہ عنہ ) کو خبر ہوگئی تو اُن کے ہاتھوں
حضرت علی اور زیادہ پریشان ہوں گے.اس گروہ کے باقی کرتا دھرتا اور لیڈر صرف نام کے مسلمان اور درحقیقت
Page 341
حفاظت قرآن کریم بر متفرق اعتراضات
325
انتہائی گھٹیا کردار کے مالک تھے.انہیں اسلامی تعلیمات کی چنداں پرواہ نہ تھی.یہ وہی خارجی تھے جنہوں نے
حضرت عثمان کو شہید کیا اور پھر حضرت عثمان کی شہادت کو مزید سیاسی عزائم کے لیے استعمال کیا.وہ مسلمانوں میں
فساد اور فتنہ پیدا کرنے کے لیے قرآن کو نیزوں پر بلند کرتے اور کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کا مطالبہ کرتے اور
حضرت علی سے مطالبہ کرتے کہ قتل عثمان کے ذمہ دار افراد سے قصاص لیا جائے.اب اگر یہ جھوٹے لوگ کہہ
رہے ہوں کہ قرآن کریم میں تحریف ہوئی ہے.پھر وہ کون سی کتاب تھی جس کے مطابق وہ فیصلہ چاہتے تھے؟
سیاسی عزائم پورے کرنے والی بے ایمان مفسد قوم جس کا علم اور ایمان سے کوئی تعلق نہیں ان کا قول جس قول کے
ساتھ کوئی دلیل بھی نہ ہو کیسے حجت ہو سکتا ہے؟ بہر حال خارجی جو بھی تھے اس کا حفاظت قرآن کے ساتھ
براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے اس لیے اس تفصیل میں جانا مضمون سے انحراف کا موجب ہوگا.صرف اتنا بیان کرنا
مقصود ہے کہ اُن کو حضرت علی کا پیرو کار قرار دینا ابن وراق کی غلط بیانی ہے.خارجی وہ پہلی قوم تھی جس نے خلفاء کی
طرف غلط باتیں منسوب کرنا شروع کیں.یہ جھوٹی تحریرات بنانے میں ماہر تھے.پس یہ تو ایک ایسا سیاسی گروہ تھا جو
عبداللہ بن سبا کے تحت ملک میں سیاسی ریشہ دوانیوں میں مشغول رہا کرتا تھا اور اپنے مزموم مقاصد کے حصول کے
لیے ایسے بیان جاری کرتے رہتے تھے جن کا مقصد صرف سیاسی منفعت تھی اور بس.خارجیوں کے بارہ میں حضرت رسول کریم ﷺ نے بطور پیشگوئی فرما دیا تھا کہ:
میرے بعد میری امت میں ایک قوم ایسی پیدا ہوگی جو قرآن کریم پڑھیں گے مگر قرآن ان
کی گردنوں سے نیچے نہ جائے گا.وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے گویا تیر کمان سے نکل جاتا
ہے.پھر وہ کبھی لوٹیں گے نہیں.وہ بدترین اخلاق والی بدترین مخلوق ہونگے.(بخاری کتاب الجهاد باب في قتال الخوارج)
ابنِ وراق کے انتخاب کی بھی داد دینی پڑتی ہے کہ صرف اس دور کے دھوکہ بازوں اور غلطی خوردہ لوگوں کے
حوالہ جات ہی اکٹھے نہیں کیے بلکہ اسلام کے ابتدائی دور میں بھی اپنے ہم تماش ڈھونڈ لیے.پہلے بنو نجار کا گمنام
عیسائی ڈھونڈ کر اُسے عبد اللہ بن سرح کا نام دیا اور اب عبد اللہ بن سبا ایک یہودی ڈھونڈ کر اُسے حضرت علی کا
پیروکار بنادیا.کسی نے کیا خوب کہا ہے.کند ہم جنس باہم جنس پرواز.لیکن اب تک کوئی ایک بھی مستند ثبوت
پیش نہیں کیا بلکہ سارا زور جھوٹ اور دجل اور تاریخی حقائق کو مسخ کر کے پیش کرنے پر ہے.پھر اس حوالہ سے بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر تاریخی شہادت نہیں ہے تو پھر قرآن کریم کے اس چیلنج کو قبول کیا
جائے.قرآن
کریم یہ چیلنج دیتا ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ قرآن کریم غیر اللہ کی طرف سے ہے تو پھر اس کی کسی سورۃ
کے برابر ان خوبیوں کا حامل کوئی کلام بنا کر دکھاؤ.یہ چیلنج بذات خود قرآن کریم کی حفاظت کی ایک دلیل اور
پیشگوئی ہے.اعتراض کیا جاسکتا ہے کہ قرآن مجید کلام الہی نہیں بلکہ انسانی کلام ہے.محض زبان سے یہ کہ دینا
Page 342
الذكر المحفوظ
326
بہت آسان ہے لیکن ثابت کرنا ناممکن ہے.اگر یہ کلام انسانی ہاتھ کا بنایا ہوا ہے تو پھر لازماً کوئی دوسرا شخص بھی ایسا
کلام بنا سکتا ہے.پس اب یہ معترض کی ذمہ داری ہے کہ اگر ایسا سمجھتا ہے کہ قرآن کریم کا کوئی حصہ انسانی ہے تو اس
کی مثل بنا کر ثابت کر دے کہ انسان ایسا کلام بنا سکتا ہے.مگر قرآن کریم کی یہ بھی پیشگوئی ہے کہ کوئی معترض مثل
نہیں بنا سکے گا.ایک طرف تو چیلنج دیا کہ قرآن کریم کے کسی بھی حصہ کی مثل لانا ہر گز تمہارے لیے ممکن نہیں ہوگا اور
سورۃ یوسف کے شروع میں
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ احسن القصص ہے.سورۃ یوسف پر اعتراض کر رہے ہو کہ الحاقی
ہے پس اپنے دعوی کو سچا کرنے کے لیے کوئی مستند ثبوت پیش نہیں کر سکتے تو سورت یوسف کی مثال بنا کر لے آؤ!
پس حقیقت تو دراصل یہی ہے جو امام الزماں علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں کہ:
یونہی دیوانوں اور سودائیوں کی طرح اوہام باطلہ پیش کرنا جن کی کچھ بھی اصلیت نہیں.اس
بات پر پختہ دلیل ہے کہ ایسے لوگوں کو راست بازوں کی طرح حق
کا تلاش کرنا منظور ہی نہیں.براہین احمدیہ چہارم حاشیہ گیارہ روحانی خزائن جلد اول صفحہ 226 ایڈیشن اول صفحہ 206 )
قرآن کریم کے نزول کے بعد تو عربی زبان کی ادبی خصوصیات زیادہ کھل کر اور نکھر کر سامنے آئیں.قرآن کریم
کی آیات کو بہترین ادبی مجموعہ قرار دیا گیا اور علم فصاحت اور علم بلاغت کی بنیاد قرآن کریم پر ڈالی گئی.اعلی ادبی
پیمانے قرآنی آیات کی روشنی میں بننے لگے.حسنِ بیان کے مثالی نمونوں کے طور پر قرآنی آیات پیش کی جاتیں.اسباب بلاغت و بداعت میں سینکڑوں قسم کے بدائع ہیں.مجاز، استعاره، کنایه، تمثیل ، تشبیه، اطناب، ایجاز،
استطراد، حسن التخلص، تضمین تجنیس ، تکرار، انسجام، ایہام، مبالغہ، مطابقہ،مقبلہ ، ارداف وغیرہ وغیرہ.آگےان
کی اقسام ہیں اہل اسلام نے قرآن کی خدمت میں صرف اسی علم کے میدان میں بے شمار علمی کارنامے سرانجام
دیے.عربی زبان میں ایسے ایسے اہل علم پیدا ہوئے جو علم فصاحت و بلاغت کے گویا استاد مانے جاتے ہیں.انہوں نے قرآن کریم کی کسی سورت کو لے کر یہ نہیں کہا کہ یہ کلام ایسا ہے کہ انسانی ہونے کا اس میں شبہ بھی
ہو سکے.بلکہ قرآنی آیات گویا پیمانہ تھیں کسی بھی اہل زبان کے حُسنِ کلام کو جانچنے کا.خارجیوں نے ایک
سورت کو لے کر یہ تو کہہ دیا کہ یہ سورت الہی کلام نہیں ہو سکتی لیکن کیا انہوں نے اپنے دعوئی کی صداقت میں کوئی
دلیل پیش کی یا قرآن کریم کا چیلنج قبول کیا اور مثال پیش کی ؟
اب یہ دیکھتے ہیں کہ خارجی جس وجہ سے سورۃ یوسف کو جائے اعتراض ٹھہراتے ہیں وہ کس حد تک درست
ہے اور خارجیوں کے حوالے سے یہ ابن وراق کا یہ کہنا کہاں تک سچ ہے کہ سورۃ یوسف میں جذبات کو انگیخت
کرنے والا بیان ہے.اس کا بہترین حل یہی ہے کہ قارئین کے سامنے سورۃ یوسف کا مکمل ترجمہ پیش کر دیا
جائے ، گو کلام کا اصل حسن تو عربی عبارت میں ہی ہے مگر اس وقت بحث حسن بیان کی نہیں بلکہ یہ ہے کہ آیا اس
سورۃ میں جذبات کو انگیخت کرنے والی کوئی بات ہے؟
Page 343
حفاظت قرآن کریم پر متفرق اعتراضات
327
ا.اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا ، بن مانگے دینے والا ( اور ) بار بار رحم
کرنے والا ہے.۲.انا الله أَرى : میں اللہ ہوں.میں دیکھتا ہوں.یہ ایک کھلی کھلی کتاب کی
آیات ہیں.۳.یقیناً ہم نے اسے عربی قرآن کے طور پر نازل کیا تا کہ تم عقل کرو.۴.ہم نے
جو یہ قرآن تجھ پر وحی کیا اس کے ذریعہ ہم تیرے سامنے ثابت شدہ تاریخی حقائق میں سے
بہترین بیان کرتے ہیں جبکہ اس سے پہلے ( اس بارہ میں ) تو غافلوں میں سے تھا.۵.(یاد
کرو) جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا اے میرے باپ ! یقیناً میں نے ( رویا میں ) گیارہ
ستارے اور سورج اور چاند دیکھے ہیں.( اور ) میں نے انہیں اپنے لیے سجدہ ریز دیکھا.۶.اس
نے کہا اے میرے پیارے بیٹے ! اپنی رویا اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا ورنہ وہ تیرے
خلاف کوئی چال چلیں گے.یقیناً شیطان انسان کا کھلا کھلا دشمن ہے.ے اور اسی طرح تیرا رب
تجھے (اپنے لئے ) کچن لے گا اور تجھے معاملات کی تہ تک پہنچنے کا علم سکھا دے گا اور اپنی نعمت تجھ
پر تمام کرے گا اور آلِ یعقوب پر بھی جیسا کہ اس نے اُسے تیرے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق پر
پہلے تمام کیا تھا.یقینا تیرا رب دائمی علم رکھنے والا (اور) حکمت والا ہے.۸.یقیناً یوسف اور
اس کے بھائیوں (کے واقعہ ) میں پوچھنے والوں کے لیے کئی نشانات ہیں.۹.(یاد کرو) جب
انہوں نے کہا کہ یقیناً یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں حالانکہ
ہم ایک مضبوط ٹولی ہیں.یقیناً ہمارا باپ ایک ظاہر و باہر غلطی میں مبتلا ہے.۱۰.یوسف کو قتل کر
ڈالو یا اُسے کسی جگہ پھینک آؤ تو تمہارے باپ کی توجہ صرف تمہارے لیے رہ جائے گی اور تم اس
کے بعد نیک لوگ بن جانا.اا.ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا یوسف کو قتل نہ کرو بلکہ اُسے
کسی کنویں کی اوجھل تہوں میں پھینک دو جو چرا گاہ کے پاس واقع ہو.اسے کوئی قافلہ اٹھالے
جائے گا.( یہی کرو ) اگر تم کچھ کرنے والے ہو.۱۲.انہوں نے کہا اے ہمارے باپ! تجھے کیا
ہوا ہے کہ تو یوسف کے بارہ میں ہم پر اعتماد نہیں کرتا جبکہ ہم تو یقیناً اس کے خیر خواہ ہیں.۱۳.اسے کل ہمارے ساتھ بھیج دے تا وہ کھاتا پھرے اور کھیلے جبکہ ہم اس کے یقیناً محافظ ہوں گے.۱۴.اس نے کہا یقینا مجھے یہ بات فکر میں ڈالتی ہے کہ تم اسے لے جاؤ اور میں ڈرتا ہوں کہ کہیں
اسے بھیڑیا نہ کھا جائے جبکہ تم اس سے غافل ہو.۱۵.انہوں نے کہا اگر اسے بھیڑیا کھا جائے
جبکہ ہم ایک مضبوط ٹولی ہیں تب تو ہم یقیناً بہت نقصان اٹھانے والے ہوں گے.۱۶.پس جب
وہ اسے لے گئے اور اس بات پر متفق ہو گئے کہ اسے ایسے کنویں کی اوجھل تہوں میں پھینک دیں
Page 344
الذكر المحفوظ
328
جو چراہ گاہ کے پاس واقع تھا تو ہم نے اس کی طرف وحی کی کہ تو (ایک دن ) یقیناً انہیں ان کی
اس کارستانی سے آگاہ کرے گا اور انہیں کچھ پتہ نہ ہوگا (کہ تو کون ہے ).۱۷ اور رات کے
وقت وہ اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے آئے.۱۸.انہوں نے کہا اے ہمارے باپ ! یقیناً
ہم ایک دوسرے سے دوڑ لگاتے ہوئے ( دُور ) چلے گئے اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے
پاس چھوڑ دیا پس اسے بھیڑیا کھا گیا اور تو کبھی ہماری ماننے والا نہیں خواہ ہم بچے ہی ہوں.۱۹.اور وہ اس کی قمیص پر جھوٹا خون لگا لائے.اس نے کہا بلکہ تمہارے نفوس نے ایک بہت
سنگین بات تمہارے لیے معمولی اور آسان بنادی ہے.پس صبر جمیل ( کے سوا میں کیا کر سکتا
ہوں ) اور اللہ ہی ہے جس سے اس (بات) پر مدد مانگی جائے جو تم بیان کرتے ہو.۲۰.اور ایک
قافلہ آیا اور انہوں نے اپنا پانی نکالنے والا بھیجا تو اس نے اپنا ڈول ڈال دیا.اس نے کہا اے
( قافلہ والو) خوشخبری! یہ تو ایک لڑکا ہے اور انہوں نے اسے ایک پونجی کے طور پر چھپالیا اور اللہ
اسے خوب جانتا تھا جو وہ کرتے تھے.۲۱.اور انہوں نے اسے معمولی قیمت چند دراہم کے عوض
فروخت کر دیا اور وہ اس کے بارہ میں بالکل بے رغبت تھے.۲۲.اور جس نے اُسے مصر سے
خریدا اپنی بیوی سے کہا اسے عزت کے ساتھ ٹھہراؤ.ہوسکتا ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم
اسے اپنا بیٹا بنالیں اور اس طریقہ سے ہم نے یوسف کے لیے زمین میں جگہ بنادی اور ( یہ خاص
انتظام اس لیے کیا ) تا کہ ہم اسے معاملات کی تہ تک پہنچنے کا علم سکھا دیں اور اللہ اپنے فیصلہ پر
غالب رہتا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے.۲۳.اور جب وہ اپنی مضبوطی کی عمر کو پہنچا تو اسے ہم
نے حکمت اور علم عطا کئے اور اسی طرح ہم احسان کرنے والوں کو جزا دیا کرتے ہیں.۲۴.اور
اُس عورت نے جس کے گھر میں وہ تھا اسے اس کے نفس کے بارہ میں پھسلانے کی کوشش کی اور
دروازے بند کر دیئے اور کہا تم میری طرف آؤ.اس (یوسف) نے کہا خدا کی پناہ! یقیناً میرا
رب وہ ہے جس نے میرا ٹھکانا بہت اچھا بنایا.یقیناً ظالم کا میاب نہیں ہوا کرتے.۲۵.اور
یقیناً وہ اس کا پختہ ارادہ کر چکی تھی اور وہ (یعنی یوسف) بھی اس کا ارادہ کر لیتا اگر اپنے رب کی
ایک عظیم بُرہان نہ دیکھ چکا ہوتا.یہ طریق اس لیے اختیار کیا تا کہ ہم اس سے بدی اور فحشاء کو دور
ہیں.یقیناً وہ ہمارے خالص کئے گئے بندوں میں سے تھا.۲۶.اور وہ دونوں دروازے کی
طرف لیکے اور اس (عورت) نے پیچھے سے (اسے کھینچتے ہوئے ) اس کی قمیص پھاڑ دی اور ان
دونوں نے اس کے سرتاج کو دروازے کے پاس پایا.اُس (عورت) نے کہا جو تیرے گھر والی
Page 345
حفاظت قرآن کریم بر متفرق اعتراضات
329
سے بدی کا ارادہ کرے اس کی جزا قید کئے جانے یا دردناک عذاب کے سوا اور کیا ہوسکتی ہے.۲۷.اس ( یعنی یوسف) نے کہا اسی نے مجھے میرے نفس کے بارہ میں پھسلانے کی کوشش کی تھی
اور اس کے گھر والوں ہی میں سے ایک گواہ نے گواہی دی کہ اگر اُس کی قمیص سامنے سے پھٹی
ہوئی ہے تو یہی سچ کہتی ہے اور وہ جھوٹوں میں سے ہے.۲۸.اور اگر اُس کی قمیص پیچھے سے پھٹی
ہوئی ہے تو یہ جھوٹ بول رہی ہے اور وہ بچوں میں سے ہے.۲۹.پس جب اس نے اس کی
قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی دیکھی تو ( بیوی سے ) کہا یقینا یہ ( واقعہ ) تمہاری چالبازی سے ہوا.یقینا تمہاری چالبازی (اے عورتو!) بہت بڑی ہوتی ہے.۳۰.اے یوسف ! اس سے اعراض
کر اور تُو (اے عورت!) اپنے گناہ کی وجہ سے استغفار کر.یقینا تو ہی ہے جو خطا کاروں میں
سے تھی.۳۱.اور شہر کی عورتوں نے کہا کہ سردار کی بیوی اپنے غلام کو اس کے نفس کے بارہ میں
پھسلاتی ہے.اس نے محبت کے اعتبار سے اس کے دل میں گھر کر لیا ہے.یقیناً ہم اسے ضرور
ایک کھلی کھلی گمراہی میں پاتی ہیں.۳۲.پس جب اُس نے اُن کی مکاری کی بات سنی تو انہیں بلا
بھیجا اور اُن کے لیے ایک ٹیک لگا کر بیٹھنے کی جگہ تیار کی اور ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک چھری
پکڑا دی اور اس ( یعنی یوسف) سے کہا کہ ان کے سامنے جا.پس جب انہوں نے اسے دیکھا
اسے بہت عالی مرتبہ پایا اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور کہا پاک ہے اللہ.یہ انسان نہیں.یہ تو ایک
معزز فرشتہ کے سوا کچھ نہیں.۳۳.وہ بولی یہی وہ شخص ہے جس کے بارہ میں تم مجھے ملامت کرتی
تھیں اور یقیناً میں نے اسے اس کے نفس کے بارہ میں پھسلانے کی کوشش کی تو وہ بچ گیا اور اگر
اس نے وہ نہ کیا جو میں اسے حکم دیتی ہوں تو وہ ضرور قید کیا جائے گا اور ضرور ذلیل لوگوں میں
سے ہو جائے گا.۳۴.اس نے کہا اے میرے ربّ! قید خانہ مجھے زیادہ پیارا ہے اس سے جس
کی طرف وہ مجھے بلاتی ہیں اور اگر تو مجھ سے اُن کی تدبیر ( کامنہ ) نہ پھیر دے تو میں ان کی
طرف جھک جاؤں گا اور میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا.۳۵.پس اس کے رب نے اُس کی
دعا کو سنا اور اس سے ان کی چال کو پھیر دیا.یقیناً وہی بہت سنے والا ( اور ) دائی علم رکھنے والا
ہے.۳۶.پھر بعد اُس کے جو آثار انہوں نے دیکھے اُن پر ظاہر ہوا کہ کچھ عرصہ کے لیے اسے
ضرور قید خانہ میں ڈال دیں.۳۷ اور اس کے ساتھ قید خانہ میں دو نو جوان بھی داخل ہوئے.ان میں سے ایک نے کہا کہ یقیناً میں ( رویا میں ) اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ میں شراب بنانے
کی خاطر رس نچوڑ رہا ہوں اور دوسرے نے کہا کہ میں ( رویا میں ) اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ
Page 346
الذكر المحفوظ
330
اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں جس میں سے پرندے کھا رہے ہیں.ہمیں ان کی تعبیر
سے مطلع کر.یقیناً ہم تجھے احسان کرنے والے لوگوں میں سے دیکھ رہے ہیں.۳۸.اس نے
کہا کہ تم دونوں تک وہ کھانا نہیں آئے گا جو تمہیں دیا جاتا ہے مگر میں تمہارے پاس اُس کے آنے
سے پہلے ہی ان (خوابوں) کی تعبیر سے تم دونوں کو مطلع کر چکا ہوں گا.یہ ( تعبیر ) اس (علم)
میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھایا.یقیناً میں اس قوم کے مسلک کو چھوڑ بیٹھا ہوں جو
اللہ پر ایمان نہیں لاتے تھے اور وہ آخرت کا انکار کرتے تھے.۳۹.اور میں نے اپنے آباء و
اجداد ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے دین کی پیروی کی.ہمارے لیے ممکن نہ تھا کہ اللہ کے
ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہراتے.یہ اللہ کے فضل ہی سے تھا جو اس نے ہم پر اور (مومن)
انسانوں پر کیا لیکن اکثر انسان شکر نہیں کرتے.۴۰.اے قید خانہ کے دونوں ساتھیو! کیا کئی
مختلف رب بہتر ہیں یا ایک صاحب جبروت الله ؟ ۴۱ تم اُس کے سوا عبادت نہیں کرتے مگر ایسے
ناموں کی جو تم نے اور تمہارے آباء واجداد نے خود ہی اُن (فرضی خداؤں) کو دے رکھے ہیں
جن کی تائید میں اللہ نے کوئی غالب آنے والی برہان نہیں اتاری.فیصلے کا اختیار اللہ کے سوا کسی
کو نہیں.اس نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا تم کسی کی عبادت نہ کرو.یہ قائم رہنے والا اور قائم
رکھنے والا دین ہے لیکن اکثر انسان نہیں جانتے.۴۲.اے قید خانہ کے دونوں ساتھیو! جہاں
تک تم دونوں میں سے ایک کا تعلق ہے تو وہ اپنے آقا کو شراب پلائے گا اور جہاں تک دوسرے
کا تعلق ہے تو وہ سُولی پر چڑھایا جائے گا پس پرندے اس کے سر میں سے کچھ ( نوچ نوچ کر )
کھائیں گے.اُس بات کا فیصلہ سنادیا گیا ہے جس کے بارہ میں تم دونوں استفسار کر رہے تھے.۴۳.اور اس نے اُس شخص سے جس کے متعلق خیال کیا تھا کہ ان دونوں میں سے وہ بچ جائے
گا کہا کہ اپنے آقا کے پاس میرا ذکر کرنا مگر شیطان نے اُسے بھلا دیا کہ اپنے آقا کے پاس
( یہ ) ذکر کرے.پس وہ چند سال تک قید خانہ میں پڑا رہا.۴۴.اور بادشاہ نے ( دربار میں )
بیان کیا کہ میں سات موٹی گائیں دیکھتا ہوں جنہیں سات دُبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں اور سات
سرسبز بالیاں اور کچھ دوسری سوکھی ہوئی بھی (دیکھتا ہوں).اے سردارو! مجھے میری رؤیا کے بارہ
میں تعبیر سمجھا ؤ اگر تم خوابوں کی تعبیر کر سکتے ہو.۴۵.انہوں نے کہا یہ پراگندہ خیالات پر مشتمل
نفسانی خواہیں ہیں اور ہم نفسانی خوابوں کی تعبیر کا علم نہیں رکھتے.۴۶.اور اس شخص نے جوان
دونوں ( قیدیوں) میں سے بچ گیا تھا اور ایک طویل مدت کے بعد اس نے (یوسف کو ) یاد کیا،
Page 347
حفاظت قرآن کریم بر متفرق اعتراضات
331
یہ کہا کہ میں تمہیں اس کی تعبیر بتاؤں گا پس مجھے (یوسف کی طرف) بھیج دو.۴۷.یوسف اے
راستباز ! ہمیں سات موٹی گائیوں کا جنہیں سات دُبلی گائیں کھا رہی ہوں اور سات سبز و
شاداب بالیوں اور دوسری سوکھی ہوئی بالیوں کے بارہ میں مسئلہ سمجھا تا کہ میں لوگوں کی طرف
واپس جاؤں شاید کہ وہ (اس کی تعبیر ) معلوم کر لیں.۴۸.اس نے کہا کہ تم مسلسل سات سال
تک کاشت کرو گے.پس جو تم کا ٹوا سے اس کی بالیوں میں رہنے دوسوائے تھوڑی مقدار کے جو
تم اس میں سے کھاؤ گے.۴۹.پھر اس کے بعد سات بہت سخت (سال ) آئیں گے جو وہ کھا
جائیں گے جو تم نے ان کے لیے آگے بھیجا ہو گا سوائے اس میں سے تھوڑے سے حصہ کے جو تم
(آئندہ کاشت کے لئے ) سنبھال رکھو گے.۵۰.پھر اس کے بعد ایک سال آئے گا جس میں
لوگ خوب سیراب کئے جائیں گے اور اس میں وہ رس نچوڑیں گے.۵۱.بادشاہ نے کہا اسے
میرے پاس لاؤ.پس جب ایلچی اس (یعنی یوسف) کے پاس پہنچا تو اس نے کہا اپنے آقا کی
طرف لوٹ جاؤ اور اس سے پوچھو ان عورتوں کا کیا قصہ ہے جو اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی تھیں.یقیناً میرا
رب ان کی چال کو خوب جانتا ہے.۵۲.اس (بادشاہ) نے پوچھا (اے عورتو!) بتاؤ تمہارا کیا معاملہ
تھا جب تم نے یوسف کو اس کے نفس کے بارہ میں پھسلانا چاہا تھا.انہوں نے کہا پاک ہے اللہ.ہمیں تو اس کے خلاف کسی بُرائی کا علم نہیں.سردار کی بیوی نے کہا اب سچائی ظاہر ہو چکی ہے.میں
نے ہی اسے اس کے نفس کے بارہ میں پھسلانا چاہا تھا اور یقینا وہ صادقوں میں سے ہے.۵۳.یہ
اس لیے ہوا تا کہ وہ (عزیز مصر ) جان لے کہ میں (یعنی یوسف) نے اس کی عدم موجودگی میں اس
کی کوئی خیانت نہیں کی اور یقیناً اللہ خیانت کرنے والوں کی چال کو سرے نہیں چڑھاتا.ترجمہ از حضرت مرزا طاہر احمد صاحب خلیفہ اسیح الرابع رحمہ اللہ )
جس پر ابن وراق کو اعتراض پیدا ہوا ہے اس بیان میں تو حضرت یوسف کی پاکیزگی، تقولی صحت نیت، خدا پر
ایمان ، اور شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے خدا تعالیٰ کی پناہ کی ضرورت کا بیان ہے.اللہ تعالیٰ یہ مضمون بیان
فرمارہا ہے کہ اگر تقویٰ اور حسن نیت ہو اور دل میں بدی کا ارادہ نہ ہوتو بھی انسان بدی سے اپنے طور پر
نہیں بچ سکتا.ہاں اگر انسان یہ تمام شرائط پوری کرے تو پھر شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے خدا تعالیٰ مددنازل کرتا ہے اور
ساتھ ہی یہ تعلیم بھی دے دی کہ اے بنی نوع اپنے نفس کی پاکیزگی نیت کی صفائی اور تقویٰ میں ترقی کرتے ہوئے
خدا تعالیٰ سے بدیوں سے بچنے کے لیے مدد طلب کرو اور اس بارہ میں بھی راہنمائی کر دی کہ انسان کو خدا کی خاطر
ابتلاء بھی برداشت کرنے پڑتے ہیں اور بد دیانت لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو جھوٹ اور دجل کی راہ سے خدا کے
Page 348
الذكر المحفوظ
332
بندوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور خدا کے بندوں کے تقویٰ اور شرافت کو دیکھ کر بھی بجائے پر نادم ہونے
کے، دل میں ٹھان لیتے ہیں کہ اس شخص کی نیکی اور تقویٰ کو زک پہنچا کر رہنا ہے اور اس کے لیے بچی بنیاد تو کوئی ملتی
نہیں پس جھوٹ اور فریب اور دھوکہ دہی سے کوشش کرتے ہیں.ایسی صورتِ حال سے اگر کوئی شخص دو چار
ہو جائے تو سوائے اللہ کے کوئی ہستی ایسی نہیں جو انسان کی حفاظت کر سکے اور اللہ حفاظت کرتا بھی ہے.پس بیان بھی قاری کے سامنے ہے اور اس سے ظاہر ہونے والی تعلیم بھی.یہ بیان پڑھ کرکس کے جذبات میں
ہیجان پیدا ہوا ہے؟ آج نام نہاد مہذب مغرب نیز دُنیا کے دیگر ممالک میں لوگ کیا سورت یوسف پڑھ پڑھ کر ان
کرتوتوں میں مبتلا ہوتے ہیں جن کا ذکر کرنا ہی ایک باغیرت اور باحیا معاشرہ میں معیوب سمجھا جاتا ہے؟ مہذب
ثقافتوں کے نام پر یورپ اور امریکہ کی عریاں کثافتیں کسی تعلیم کا ثمرہ ہیں؟ آج کی مہذب دنیا میں پھیلی بے غیرتی
اور بے حیائی کس تعلیم کا نتیجہ ہے؟ حز قیل باب 23 کی تعلیم کا؟ کون سا نام نہاد مسلمان ہے جو یورپ کے گھر گھر پائی
جانے والی دیوثی جیسی دیوٹی کا مرتکب ہونے کے لیے سورت یوسف کا حوالہ دیتا ہے؟ اس پاکیزہ تعلیم کے مطالعہ
سے تو انسان خدا تعالیٰ کے اور قریب ہوتا ہے اور خدا کی محبت اور نیکی کی محبت اور تقویٰ میں ترقی کرتا ہے.یہ ساری سورت حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے واقعات سے تعلق رکھتی ہے.مثلاً آپ کے
ساتھ جو دو قیدی تھے ان دونوں کی رؤیا کی حضرت یوسف نے ایسی تعبیر فرمائی جو بعینہ پوری ہوئی اور اسی وجہ سے
وہ قیدی جس کے بچنے کی خوشخبری دی گئی تھی ، ذریعہ بن گیا کہ بادشاہ کی اس رؤیا کے متعلق حضرت یوسٹ سے
تعبیر طلب کرتا جس کو درباری علما نے محض نفس کے خیالات سے تعبیر کیا تھا اور حضرت یوسف کی تعبیر ہی کے عین
مطابق یہ عظیم الشان واقعہ ہوا کہ مصر اور اس کے اردگرد ایسے غربا جنہوں نے یقینا فاقوں سے مر جانا تھا فاقہ کشی
کے عذاب سے بچائے گئے اور مسلسل سات برس تک ان کو غذا مہیا کی گئی اور اس انتظام کے نگران خود
حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بنائے گئے اور اسی وجہ سے بالآخر آپ کے والدین اور بھائیوں کو آپ ہی کی
پناہ میں آنا پڑا اور وہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو گئے.یہ تاریخ کے ایسے واقعات ہیں جن کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی صورت ذاتی علم نہیں ہو سکتا تھا اس لیے
فرمایا کہ تو ان لوگوں میں موجود نہیں تھا جب یہ سب کچھ رونما ہو رہا تھا.یہ محض ایک علیم وخبیر اللہ ہی ہے جو تجھے ان
واقعات کی حقیقت سے آگاہ فرما رہا ہے.غالبا سورت یوسف میں بیان فرمودہ اس واقعہ پر ابن وراق اپنے اعتراض کی بنیاد رکھ رہا ہے جس میں
حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک عورت نے آپ کی مرضی کے خلاف ایک ناجائز فعل میں الجھانا چاہا.مگر سارا
واقعہ پڑھ جائیں تو روح آستانہ الوہیت پر سجدہ ریز ہوتی ہے کجا یہ کہ جذباتی ہیجان پیدا ہو.جب کہ بائیل میں
Page 349
حفاظت قرآن کریم پر متفرق اعتراضات
333
ایسی باتیں پائی جاتی ہیں کہ پڑھ کر ہی شرم آتی ہے.مثلاً حضرت لوط پر اپنی بیٹیوں سے زنا کے بیہودہ الزامات کا
شرمناک بیان ( پیدائش 36-19/31 ) اور حضرت نوح پر شراب نوشی اور نشہ کی حالت میں برہنہ ہو جانے کے لچر
الزامات ( پیدائش 25-9/20) اور حز قیل نبی کی کتاب کے باب 23 کا حیاسوز بیان جو یورپ کے عیسائی سے تو
بعید نہیں مگر اسلامی دنیا میں رہنے والے کسی عیسائی کے لیے بھی اپنے گھر میں ماں بیٹی کے سامنے پڑھنا مشکل ہوگا.سورت یوسف پر اعتراض کے بعد سورۃ الشورای کی چند آیات کے بارہ میں بلا ثبوت کہتا ہے کہ:
On the other hand, most scholars do believe that
there areinterpolations in the Koran; these interpolations
can be seen as interpretative glosses on certain rare
words in need of explanation.More serious are the
interpolation of a dogmatic and political character, such
as 42.36-38, which seems to have been aded to justify the
elevation of Uthman as caliph to the detriment of Ali.Then there are other verses that have been added in the
interest of rhyme, or to join togather two short passages
connection.that on their own lack
any
(Ibn Warraq: Why I am Not A Muslim, Prometheus Books, New
York, 1995, under heading; The Koran: Pg: 112)
پھر اکثر محققین بھی یہ یقین رکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں تحریف ہوئی ہے.یہ تحریفات غیر واضح
الفاظ کی تفسیر و توضیح میں لکھے گئے تشریحی جملوں کی صورت میں دیکھی جاسکتی ہیں.زیادہ سنجیدہ تحریفات
اعتقادی اور سیاسی نوعیت کی ہیں ، جیسا کہ 38-42.36 جو کہ ( حضرت ) عثمان (رضی اللہ عنہ )
کو بطور خلیفہ (حضرت) علی (رضی اللہ عنہ ) سے زیادہ حق دار ثابت کرنے کے لیے داخل کی گئی
ہیں.پھر دوسری قسم کی آیات وہ ہیں جو شاعرانہ تنگ بندیاں جوڑنے کے لیے داخل کی گئی ہیں یا ایسی
دو آیات کا باہمی ربط پیدا کرنے کے لیے ڈالی گئی ہیں جن کا دراصل آپس میں کوئی تعلق نہیں بنتا.ابن وراق کے اس دجل کے جواب میں ہم ایک جانے مانے مستشرق ویلیم میور کے الفاظ درج کر دیتے ہیں.No early or trustworthy traditions throw suspicion
upon Othman of tempering with the Coran in order to
support his own claim.The Sheeah of later times,
indeed, pretend that Othman left out certain Suras of
which favoured Ali.But this is incredible......At
passages
the time of the recension, there were still multitudes
alive who had the Coran, as originally delivered, by
heart; and of the supposed passages favouring Ali had
any ever existed there would have been numerous
transcripts in the hands of his family and followers.Both
Page 350
334
الذكر المحفوظ
of these sources must have proved an effectual check
upon any attempt or suppression.(William Muir, Life of Mohamet, London, 1894, Pg: 558-559)
کسی بھی پرانی اور معتبر روایت سے ذرہ بھر شک کرنے کی وجہ پیدا نہیں ہوتی کہ حضرت عثمان
نے اپنے دعوی کی تائید میں قرآن شریف میں ایک ذرہ بھی تصرف کیا ہو.اس میں شک نہیں کہ
متاخرین شیعوں نے یہ غلط بات گھڑ رکھی ہے کہ حضرت عثمان نے بعض سورتیں اور آیات جو
حضرت علیؓ کے حق میں تھیں، عمداً قرآن میں درج نہ کرنے دی تھیں.لیکن شیعوں کی یہ بات
بالکل قابل اعتبار نہیں...حضرت عثمان کے تدوین قرآن کے وقت ابھی ہزار ہا ایسے حفاظ صحابہ
زندہ تھے جنہوں نے وقت نزول سے ہی قرآن شریف کو سن کر حفظ کر لیا ہوا تھا اور اگر حضرت علیؓ
کے حق میں کوئی ایسی سورت یا آیت ہوتی تو ضرور اہل خانہ اور ہزار ہا دیگر ایسے لوگوں کے پاس
محفوظ ہوتی جو حضرت علی کے ساتھ اخلاص اور تعلق رکھتے تھے.یہ دونوں ذرائع ایسی جسارت یا
تصرف کو ثابت کرتے اور مؤثر انداز میں اس کی روک تھام کرتے.اس جواب کے ساتھ ساتھ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ذیل میں یہ آیات ترجمہ کے ساتھ درج کر دی جائیں.قاری
خود فیصلہ کر لے کہ کہاں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حق تلفی کی بات ہورہی ہے.ص
فَمَا أُوتِيتُم مِّنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ وَّ اَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا
ج
وَ عَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وَ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَّرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَ إِذَا مَا
غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ O وَ الَّذِينَ اسْتَجَابُو لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلوةَ من وَأَمُرُهُمُ
شُورَى بَيْنَهُمُ ص وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنْفِقُونَ (آیات 37 تا 39)
ترجمہ : اور جو کچھ بھی تم کو دیا گیا ہے وہ ورلی زندگی کا سامان ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس
ہے وہ مومنوں اور اپنے رب پر توکل کرنے والوں کے لیے زیادہ اچھا اور زیادہ باقی رہنے والا
ہے اور (ان کے لیے ) جو بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اور جب ان کو غصہ آتا ہے تو معاف
کر دیتے ہیں اور جو اپنے رب کی آواز کو قبول کر لیتے ہیں اور نمازیں باجماعت ادا کرتے ہیں
اور ان کا طریق یہ ہے کہ اپنے ہر معاملہ کو باہمی مشورہ سے طے کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان
کو دیا ہے اُس میں سے خرچ کرتے ہیں.اب ان آیات میں کہاں سیاسی نوعیت کی ہیرا پھیری ہے؟ صاف اور سیدھا سادا مضمون ہے.مومنوں کو تعلیم
دی جارہی ہے کہ اگر اعلیٰ درجہ کے مومن بنتا ہے تو تمہیں چاہیے کہ ان ان خصوصیات کے حامل بنو.
Page 351
حفاظت قرآن کریم پر متفرق اعتراضات
335
رض
پھر ایک سوال یہ ہے کہ حضرت علیؓ نے کیوں اس نسخہ پر کوئی اعتراض نہ کیا ؟ حالانکہ آپ نے تو خود بھی قرآن
جمع کیا تھا اور حافظ قرآن بھی تھے.پس آپ کو بکلی اتفاق تھا اور تسلی تھی جس کا نہج البلاغہ میں درج آپ کے
خطبات میں بار بار ذکر ملتا ہے.پھر یہ بھی غور طلب بات ہے کہ حضرت عمر با وجود انتہائی اہم سمجھنے کے رجم کے
ایک حکم کو تو قرآن کریم کے حاشیہ میں بھی درج نہیں کرتے کہ مسلمان اعتراض کریں گے گجا یہ کہ اتنی بہت سی
آیات متن قرآن کا حصہ بنادی جائیں اور صحابہ میں سے کوئی آواز بلند نہ ہو.پھر ایک سوال یہ بھی ہے کہ اگر کوئی
آیت ڈالی گئی تھی تو حضرت علیؓ نے اپنے عہد خلافت میں اس کو نکال کیوں نہیں دیا؟ نیز کیوں خارجیوں نے اس
آیت کے نکالنے پر اصرار نہ کیا ؟ آخر مکمل سورۃ یوسف کی نسبت چند آیات کا نکالنا زیادہ آسان تھا.سورۃ یوسف پر
تو اعتراض کر دیا مگر ان آیات پر نہ کیا.پھر بقول ابن وراق خارجی تو حضرت علی کے پیروکار تھے.اپنے آقا کی حق
تلفی پر کیوں خاموش رہے؟ اور جب حضرت
علی کا عہد خلافت شروع ہوا تو پھر ان آیات کو نکالنے میں کیا روک تھی ؟
جہاں تک اس وسوسہ کا تعلق ہے کہ بعد میں شامل کی گئی آیات میں سے دوسری قسم کی آیات وہ ہیں جو
شاعرانہ تک بندیاں جوڑنے کے لیے داخل کی گئی ہیں یا ایسی دو آیات کو آپس میں جوڑنے کے لیے ڈالی گئی ہیں جن
کا دراصل آپس میں کوئی تعلق نہیں بنتا.تعجب ہے کہ یہ شاعرانہ تگ بندیاں آج ابن وراق
کو تو نظر آ گئیں مگر اہل کمال
عرب سخن وروں ، لبید، طفیل، ضمار از دی ، عمرو بن جموح و غیرہ کو علم ہی نہ ہوا کہ جس کلام
کو وہ بلندشان اور غیر معمولی
سمجھ کر کلام الہی تسلیم کر بیٹھے ہیں وہ تو ابھی غیر مربوط آیات ہیں اور آئندہ ابھی کچھ آیات شامل کرنے کے بعد اس
قابل ہوگا کہ یہ مربوط کلام قرار دیا جاسکے.پس یہ اعتراض تو محض دیوانوں اور سودائیوں کے اوہام باطلہ ہیں.ایسے اعتراضوں کا اصولی جواب تو دیا جا چکا ہے کہ نہ تو تاریخ سے ثابت ہے کہ بعد کے زمانہ میں کوئی آیت
شامل کی گئی ہو اور نہ ہی آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے یہ توقع کی جاسکتی ہے اور نہ ہی خاموشی سے
ایسا کرنا ممکن تھا اور نہ ہی آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ اخلاق فاضلہ کی بلندیوں پر فائز صحابہ سے ایسی
بددیانتی متصور ہو سکتی ہے اور نہ ہی صحابہ اور اہل زبان علما ایسی آیات کی موجودگی قرآن کریم میں تسلیم کرتے ہیں.کسی آیت کی یا کسی حصہ کی ترتیب یا آیات کا باہمی ربط سمجھ نہ آنا ایک دیگر امر ہے اور اس کے بارہ میں یہ
دعوی کرنا کہ دلائل سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ آیت بعد میں شامل کی گئی ہے امر دیگر ہے.ہم جمع و تدوین قرآن کے
بارہ میں یہ بات وضاحت سے دیکھ آئے ہیں کہ تمام تر حقائق کے مطالعہ سے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ قرآن کریم بعینہ
اسی حالت میں محفوظ ہے جس حالت میں خدا تعالیٰ نے نازل کیا.تمام تر آیات پر امت مسلمہ نے گواہی دی تھی
کہ یہ قرآن کریم کی ہی آیات ہیں جو انہوں نے رسول کریم سے حفظ کے ذریعہ اور تحریری صورت میں حاصل کی
تھیں اور پھر وہ قرآن کریم ایک نہ ٹوٹنے والے تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے.چنانچہ اس بات کے ثبوت میں
Page 352
الذكر المحفوظ
336
کہ قرآن کریم بعینہ وہی ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے امت کو ملا تھا، یہ ذکر گزر چکا کہ
حضرت عثمان کے عہد خلافت میں صحابہ کے اتفاق رائے سے تیار ہونے والا مصحف امام 25 ھجری کے لگ بھگ
تیار ہو چکا تھا اور اس کی نقول بلاد اسلامیہ میں اشاعت کی غرض سے بھجوائی جا چکی تھیں وہ آج بھی موجود ہے.جبکہ حضرت ابوبکر کے دورِ خلافت میں صحابہ کی گواہی سے تیار ہونے والا مصحف ام مروان بن عبد الملک کے دور
تک یعنی 50 هجری تک موجود رہا ہے.گویا یہ دونوں نسخے 25 سال تک اکٹھے موجود رہے ہیں.کسی دوست یا
دشمن نے کبھی یہ اعتراض نہیں کیا کہ مصحف امام میں ایسی کوئی آیات موجود ہیں جو مصحف ام میں نہیں ہیں اور نہ
ہی کبھی حفاظ نے یہ اعتراض اٹھایا کہ مصحف امام میں ایسی آیات درج کی گئی ہیں جو انہوں نے پہلے کبھی نہ سنیں
اور نہ حفظ کی تھیں.حضرت عثمان کے دور کے صحائف آج بھی موجود ہیں.پس اس تواتر کے ہوتے ہوئے کون
محافظت قرآن کریم کے باب میں ادنی سا بھی شبہ پیدا کر سکتا ہے؟
پھر ہر زمانہ میں اختلاف مذہب کے باوجود محققین قرآن کریم کی غیر معمولی حفاظت کی گواہی دیتے آئے ہیں.ان سب نا قابل تردید شہادتوں کے باوجود بھی یہ بات ان نام نہاد سکالرز کو سمجھ نہیں آرہی کہ تاریخی دلائل سے قرآن کریم کی
صحت اور اس کے ہر ہر لفظ کا مستند ہونا ثابت ہے.پس ان ثبوتوں کے مقابل پر یہ کہنا کہاں کا انصاف ہے کہ چونکہ
اس آیت کا ربط عربی سے نابلد ایسے لوگوں کو نظر نہیں آیا جو اسلام کے خلاف دلوں میں بیجا کینہ، بغض اور تعصب رکھتے
ہیں اس لیے ثابت یہ ہوا کہ فلاں آیت قرآن کریم کے اصل متن کا حصہ نہیں بلکہ الحاقی ہے اور بعد میں شامل کی گئی
ہے.یہ تو ایک بھونڈ امذاق اور تمسخر ہے.یہ بھی تو دیکھو کہ کتنے ہی اہل علم اور اہل زبان علما ند ہی اختلاف کے باوجود
قرآن کریم کے کے غیر معمولی ربط اور ترتیب اور اسلوب بیان کے اعجاز کو تسلیم کرتے آئے ہیں.پس اُن کے مقابل
پر تمہاری حیثیت ہی کیا ہے کہ تمہاری بات تسلیم کی جائے ! میاں دلائل کی رو سے ثابت کرو کہ یہ آیت بعد میں ڈالی گئی
ہے.ثبوت دو کہ پہلے یہ آیت متن قرآن میں موجود نہیں تھی اور فلاں زمانہ میں قرآن کریم میں راہ پاگئی.یہ کیا کہ آج
اُٹھ کر یہ کہ دیا جائے کہ یہ آیت قرآن کا حصہ نہیں ہوسکتی کیونکہ مجھے اس کا ربط سمجھ نہیں آرہا؟
نزول کے زمانہ میں قرآن کریم کا غیر معمولی فصاحت و بلاغت کا دعوی ہو اور اہل زبان بھی کبھی چیلنج کے
جواب میں خاموش رہ کر اور کبھی بآواز بلند قرآن کریم کی فصاحت اور اس کے غیر معمولی حسنِ بیان کا اعتراف
کریں لیکن ایک عربی زبان سے نابلد اُٹھ کر یہ اعتراض کر دے کہ قرآن کریم کی عبارت میں ربط و تسلسل نہیں تھا
اس لیے کچھ آیات ربط پیدا کرنے کے لیے بعد میں شامل کی گئیں.رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے دور سے
لے کر آج تک عربی جاننے والے قرآن کریم کے حسنِ بیان اور حیرت انگیز فوق البشر اسلوب کا اعتراف کرتے
چلے آئے ہیں.اگر عربی سے نابلد کوئی شخص یہ کہہ دے کہ سب جھوٹ ہے تو اس کو یہ حسن دکھانا ایسا ہی ہے جیسے
کسی اندھے کا دماغ خراب ہو جائے اور وہ کسی خوبصورت لالہ زار میں بیٹھا چلا رہا ہو کہ بہت بُری جگہ ہے.ا
Page 353
حفاظت قرآن کریم بر متفرق اعتراضات
337
جب کوئی اُسے بتائے کہ میاں یہ جگہ تو بہت خوبصورت ہے تو وہ کہہ دے کہ تم غلط کہہ رہے ہو کیونکہ مجھے تو کوئی
خوبصورتی نظر نہیں آتی.پس ثابت ہوا کہ اس لالہ زار میں کوئی خوبصورتی ہے ہی نہیں.پھر تو یہی کیا جاسکتا ہے کہ میاں
ہماری بات کا یقین نہیں ہے تو اوروں سے پوچھ لو جو اس حسن کا خود مشاہدہ کر چکے ہیں.لیکن اگر وہ اندھا ابن وراق ہو
تو ایک اور مشکل پیش آجاتی ہے.وہ بجائے آنکھ والوں سے پوچھنے کے کسی دوسرے اندھے کے پاس چلا جاتا ہے اور
اس سے پوچھنے لگتا ہے کہ تم بتاؤ وہاں تم نے کوئی حسن دیکھا ہے.ابن وراق بھی عربی کے حسن ترتیب کا انکار کرتے
ہوئے یہی ثبوت دیتا ہے کہ دیکھ لوفلاں فلاں عربی سے نابلد انسان بھی قرآن کریم کا حسن بیان
نہیں دیکھ سکا.قرآن کریم کی حسنِ ترتیب پر بات ترتیب قرآن کے باب میں
کی گئی ہے.یہاں صرف تحریف کے حوالے سے
گفتگو کرتے ہوئے یہی عرض ہے کہ جب تمہیں اپنی جہالت کی وجہ سے دو آیات کا باہمی ربط نظر نہیں آتا تو اہل علم
سے پوچھ لیا کرو.اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے:
فَاسْتَلُوا أَهْلَ الذِكر ان كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (النحل : 44)
یعنی اگر کسی معاملے میں سمجھ نہ آئے تو اس علم کے ماہرین سے پوچھ لیا کرو.پس ہم ابن وراق کو یہی فلسفہ پھر سمجھاتے ہیں جو ان
کی سمجھ میں نہیں آتا اور ان کے لیے بہت ہی مشکل اور گہرا
واقع ہوا ہے کہ صاحب ! اگر قرآن کریم کا حسنِ بیان عربی زبان سے عدم واقفیت کی وجہ سے آپ کے بس کا
روگ نہیں ہے تو پھر ان گواہیوں پر اعتبار کر لو جو اُس دور کے اہل زبان دے چکے ہیں.قرآن کریم کی تفسیر میں
ہزاروں ہزار صفحات لکھے گئے ہیں جن میں اس کے معجز نما ربط کا بھی بیان ہے اور زبان کی شیرینی کا بھی.جو شخص اتنی
سی بات نہیں سمجھ سکتا کیسے ممکن ہے کہ وہ قرآن کریم کی آیات کے گہرے باہمی ربط کو سمجھ سکے؟ آخر یہ فلسفہ اتنا گہرا تو
نہیں کہ سمجھ میں ہی نہ آئے کہ جو شخص عربی نہیں جانتا وہ عربی زبان کے حسن کا خود مطالعہ نہیں کرسکتا.ایسے شخص کے
لیے کلام کے حسن کو سمجھنے کے لیے اس زبان کے ماہر کی خدمات لینا ضروری امر بن جاتا ہے اور ہم گزشتہ سطور میں
تکرار کے ساتھ بیان کر چکے ہیں کہ ابنِ وراق کی مشکل حل کرنے کے لیے علامہ سیوطی کی گواہی کافی ہے.خارجیوں کا ذکر کرنے کے بعد ابن وراق اہل تشیع کے حوالہ سے شبہ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے:
Shiites, of course, claim that Uthman left out a great
many verses favorable of Ali for political reasons.یقیناً اہل تشیع کا بھی دعوی ہے کہ (حضرت) عثمان نے بہت سی ایسی آیات جو کہ
( حضرت ) علی کی مؤید تھیں محض سیاسی وجوہات کی بنا پر چھوڑ دی ہیں.یہ کہنا بالکل جھوٹ اور دجل ہے کہ اہل تشیع کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن میں تحریف ہوئی ہے.شیعہ ہرگز ایسا
عقیدہ نہیں رکھتے بلکہ اس کو کلیۂ رڈ کرتے ہیں.اکابر علماء شیعہ جن کے اقوال و تحقیقات کے محور پر آسمان تشیع کی
Page 354
الذكر المحفوظ
338
گردش ہے قرآن کریم کی عدیم النظیر حفاظت کے قائل ہیں اور جابجا اس حقیقت کی تصریح کرتے ہیں کہ ہم
قرآن مجید میں کسی قسم کی تحریف و تبدل کے قائل نہیں.مناسب ہوگا کہ اہل تشیع کی زبان سے ہی ابنِ وراق کے
اس الزام کی تردید کی جائے.چنانچہ معروف اور اہم شیعہ کتاب مجمع البیان میں لکھا ہے:
فاما الزيادة فيه فجمع على بطلانه و اما النقصان منه فقد روى جماعة
من اصحابنا و قوم من حشوية العامة ان فى القرآن تغييرا و نقصانا و
الصحيح من مذهب اصحابنا خلافه و هو الذي نصره المرتضى قدس
الله روحه و استوفى الكلام فيه غاية الاستيفاء في جواب المسائل
الطرابلسيات و ذكر في مواضع ان العلم بصحه نقل القرآن كالعلم
بالبلدان والحوادث الكبار و الوقائع العظام والكتب المشهورة و
اشعار العرب المسطورة فان العناية اشتدت والدواعى توفرت على نقله
و حراستـه و بـلـغـت الى حد لم يبلغه فيما ذكرناه لان القرآن معجزة
النطوة و ماخذ العلوم الشرعية والاحكام الدينية علماء المسلمين قد
بلغوفي حفظه و حماية الغاية حتى عرفو كل شيء اختلف فيه من
اعرابه و قرائته و حروفه و آياته فكيف يجوز ان يكون مغيرا او منقوصا
العناية الصادقة و الضبط الشديد
(ابوالفضل بن الحسن الطبرسي: مجمع البيان الجزء الاول: الفن الخامس
صفحه 15 : الناشر مكتبه علميه الاسلاميه (ملتان)
جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ قرآن کریم میں کچھ اضافہ ہوا ہے تو یہ بات سب کے
نزدیک غلط ہے.باقی رہی کمی کی بات تو اگر چہ ہماری (اہل تشیع ) جماعت میں سے ایک گروہ
نے اور اہلِ سنت میں سے حشویہ روایت کیا ہے کہ قرآن کریم میں تغیر اور کمی ہوگئی ہے لیکن
ہمارے فرقہ کا صحیح مذہب اس کے خلاف ہے اور حضرت سید علی مرتضی قدس اللہ روحہ نے اسی کی
تائید کی ہے اور مسائل الطرابلسیات کے جواب میں اس پر نہایت مفصل بحث کی ہے.سید ناعلی
نے متعدد مواقع پر فرمایا ہے کہ قرآن کی صحت کا علم ایسا ہی ہے جیسا شہروں کا علم اور بڑے بڑے
واقعات اور مشہور کتاب اور عرب کے مدون اشعار کا علم کیونکہ قرآن کی نقل اور حفاظت کے
اسباب کثرت سے موجود اور مہیا تھے اور اس حد تک پہنچے ہوئے تھے کہ کسی اور چیز کے سنے نہیں
گئے.اس لیے قرآن نبوت کا معجزہ اور علوم شرعیہ اور احکام دینیہ کا مآخذ ہے اور مسلمان علمانے
اس کی حفاظت اور حمایت میں انتہا درجہ کی کوشش کی.یہاں تک کہ قرآن کے اعراب، قراءت،
Page 355
حفاظت قرآن کریم پر متفرق اعتراضات
339
حروف اور آیات کے فرق تک انہوں نے محفوظ رکھے.اس لیے کیوں کر خیال کیا جاسکتا ہے کہ
اس قدر راحتیاط کے ہوتے ہوئے اس میں کسی قسم کی تغیر یا کمی راہ پا جائے؟
حضرت علی کے بارہ میں یہ ذکر گزر چکا ہے کہ حضرت ابوبکر کے دور میں جمع قرآن پر آپ کو کسی قسم کا کوئی
اعتراض نہ تھا.حضرت عثمان کی خدمت قرآن کے بارہ میں تو آپ فرماتے ہیں:
لو لم يصنعة لصنعته (كتاب المصاحف الجزء الاول صفحه 12)
یعنی اگر عثمان یہ کام نہ کرتے تو میں یہ خدمت سر انجام دیتا.آپ کا یہ قول اس بات پر گواہ ہے کہ حضرت عثمان
نے جب اس نسخہ قرآن کو شائع کیا تو آپ اس وقت بھی متفق تھے اور بعد میں اپنے دور خلافت میں بھی حضرت علیؓ
کا اسی قرآن کریم پر انحصار کرتے رہنا اور اسے ہی حجت کے طور پر پیش کرنا ایک ناقابل تردید تاریخی ثبوت
ہے.(نہج البلاغہ خطبہ 125 ) چونکہ بات اہل تشیع کے حوالہ سے ہورہی ہے اس لیے شیعوں کی مستند کتاب نہج البلاغہ
میں حضرت علی کے خطبہ نمبر 18 اور خطبہ نمبر 127 کا مطالعہ فائدہ مند رہے گا.ان خطبات میں حضرت علی نے
حضرت عثمان کی خدمت قرآن پر اپنی رضامندی، خوشنودی اور اطمینان کا اظہار کیا ہے اور اُمت کو اسی قرآن پر
قائم رہنے کی نصیحت فرمائی ہے.علامہ الطبرسی اپنی تحقیق پیش کرنے کے بعد اپنی تائید میں ایک اور عالم کا حوالہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں :
و كذالك القول في كتاب المزني.....ان القرآن كان على عهد
رسول الله مجموعا مؤلفا على ما هو عليه الآن
(مجمع البيان الجزء الاول : الفن الخامس صفحه 15 : مكتبه علميه الاسلاميه ملتان)
علامہ مزنی نے اپنی کتاب میں یہی بیان فرمایا ہے...کہ قر آن رسول کریم کے دور میں ہی
جمع ہو گیا تھا اور اسی طرح تالیف ہو گیا تھا جیسا کہ آج کے دور میں ہے.اہل تشیع میں بہت قدر و منزلت کی حامل معروف شیعہ تفسیر بحارالانوار میں لکھا ہے:
إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِكرَ وَإِنَّا لَهُ لَحفِظُونَ - (الحجر: 10 ) عن الزيادة و النقصان و
التغير و التحريف وقيل نحفظه من كيد المشركين فلا يمكنهم ابطاله
ولا يندرس و ينسى
(علامة مجلسى بحار الانوار؛ مؤسسة الوفاء ؛ بيروت لبنان ایڈیشن 4(1983) جزء
۹ صفحه 113 باب احتجاج الله تعالى على ارباب الملل المختلفة في القرآن الكريم )
یعنی آیت إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ.(الحجر: 10) کا مطلب ہے کہ ہم
اس کتاب کی حفاظت کریں گے.پس اس میں نہ تو کسی قسم کا کوئی اضافہ ممکن ہے نہ کوئی کمی.نہ
Page 356
الذكر المحفوظ
340
کوئی تبدیلی ممکن ہے اور نہ کوئی تحریف اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ
مشرکوں کے منصوبوں کے مقابل پر ہم اس کی حفاظت کریں گے اور ان کے لیے اس کا ابطال
ممکن نہیں رہے گا اور نہ یہ پس پشت ڈالی جائے گی اور نہ ہی بھلائی جائے گی.پھر علامہ مجلسی قرآن کریم کی آیت سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسى إِلَّا مَا شَاءَ اللہ کے بارہ میں شیعہ عقیدہ کی یوں
وضاحت کرتے ہیں:
اما قوله " إِلَّا مَا شَاءَ الله ، ففيه احتمالان - احدهما ان يقال هذه الاستثناء
66
غير حاصل في الحقيقة و أنه لم ينس بعد نزول“
(بحار الانوار جزء ۱۷ صفحه ۹۷ باب ١٦ سهوه و نومه عن الصلواۃ ایڈیشن ٤
مكتبه مؤسسة الوفاء بيروت لبنان ٥١٤٠٤ بمطابق (1983)
یعنی جہاں تک اللہ تعالیٰ کے اس قول إِلَّا مَا شَاءَ اللہ “ کا تعلق ہے تو اس میں دو احتمال ہیں جن میں سے
ایک یہ ہے کہ یہ استثناء غیر حاصل ہے اور در حقیقت قرآن کریم نزول کے بعد کبھی نہیں بھلایا گیا.پھر علامہ بیضاوی کا موقف بھی اپنے مؤقف کی تائد میں بیان کرتے ہیں:
وقيل المراد به القلة أو نفى النسيان رأسا
(بحار الانوار جزء ۱۸ صفحه ۱٧٤ باب : ۱ ، المبعث و اظهار الدعوه و ما لقى من
القوم...ایڈیشن ٤ مكتبه مؤسسة الوفاء بيروت لبنان ٥١٤٠٤ بمطابق 1983)
یعنی اس کے مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس سے گھولنے کی قلت یا کلیپ نفی مراد ہے.پس اتنی واضح شہادتوں کی موجودگی میں یہ کہنا کہ اہل تشیع کا یہ عقیدہ ہے کہ کہ قرآن کریم میں تحریف ہوئی ہے
ایک واضح جھوٹ نہیں تو اور کیا ہے؟ شیعہ عالم ملا فتح اللہ کا شانی سچ کہتے ہیں کہ:
هر کس بما شیعه نسبت زهد که میگوئیم از قرآن
چیزی نقصان یافته دروغ میگوید و ما هرگز چنین
سخن نگوئیم
لافتح اللہ کاشانی بنج الصادقین مقدمة الكتاب صفحہ 15)
وہ سب لوگ جو شیعہ فرقہ کی نسبت یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں کوئی کمی ہوگئی ہے وہ جھوٹ
بولتے ہیں.ہم ہرگز ایسی بات نہیں کہتے.ایسا جھوٹ تو کوئی بھی گھڑ سکتا ہے.ابن وراق بھی شیعہ فرقہ سے تعلق کا دعویٰ کرتا ہے.اگر کوئی ابن وراق کی
جہالت کے حوالہ سے ہی یہ اعتراض کرنا شروع کر دے کہ شیعہ نہ اسلام کو سچا مانتے ہیں نہ قرآن کو کلام الہی تسلیم
کرتے ہیں اور نہ ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کو خدا کا رسول سمجھتے ہیں.تو کیا یہ ہرزہ سرائی شیعہ فرقہ کا
Page 357
حفاظت قرآن کریم بر متفرق اعتراضات
341
عقیدہ بن جائے گا؟ پس چند متعصب جاہلوں کی رائے کو کسی قوم کی رائے قرار نہیں دیا جاسکتا.جہاں تک اس بات
کا تعلق ہے کہ ایسی روایات تاریخ کی کتب میں کیوں ملتی ہیں؟ تو اہل علم جانتے ہیں کہ اہل اسلام
نے اپنے دور میں دشمنانِ اسلام کی طرف سے پھیلائی جانے والی افواہوں وغیرہ کو بھی انتہائی دیانت داری کے
ساتھ تاریخی امانت سمجھ کر دنیا کے سپرد کیا ہے اور جیسی روایات بھی منافقوں یا غیر مسلموں کی طرف سے پھیلائی جارہی
تھیں ان کو بعینہ درج کرنا اپنی ذمہ داری سمجھا.ہاں ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے چلے گئے کہ یہ روایات غلط ہیں اور ان کا
کوئی سر پیر نہیں ہے.صرف آئندہ زمانہ کے لوگوں کے علم کے لیے یہ خبریں آگے منتقل کی جار ہیں تا کہ انہیں علم ہو کہ
ہر زمانہ میں دشمن زور لگا تارہا ہے مگر اپنے مزموم مقاصد میں کبھی کامیاب نہیں ہوا.یہ رائے صرف ہماری ہی نہیں بلکہ
دیانت دار مستشرقین بھی اس
کو تسلیم کرتے ہیں.چنانچہ مشہور رومن کیتھولک بن اور مشرقی علوم کی ماہر کیرم آرمسٹرانگ
اسلامی تاریخ کے ابتدائی مآخذ اور مشہور مسلمان مؤرخین ابن الحق ، ابن سعد ، طبری اور واقدی کے بارہ میں مھتی ہیں:
یہ چاروں بہت معتبر مؤرخ اور سوانح نگار ہیں.ان سوانح نگاروں کے ہاں آپ کو محض ان کے
خیالات اور معتقدات ہی نہیں ملتے بلکہ حقائق کو تلاش کرنے کی محققانہ کاوش بھی دکھائی دیتی ہے.مثلاً
انہوں نے تمام ابتدائی اور بنیادی دستاویزات کو پڑھا، سینہ بسینہ چلی آرہی روایات و حکایات کو سنا اور
اس کے باوجود کہ وہ سچے مسلمان تھے اور نبی کریم ﷺ کی ذات مبارک سے گہری عقیدت رکھتے
تھے، تاریخ لکھتے ہوئے کم ہی دکھائی دیتا ہے کہ وہ کسی معاملے میں جانب دار ہوئے ہوں....ان
سوانح عمریوں کی درستگی پر اعتبار کرتے ہوئے ہم یہ بات پورے وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ ان کی بنیاد پر
ہم نبی (ع) کی حیات مبارکہ کا ایک زیادہ حقیقت پسندانہ اور سچا خا کہ حاصل کر سکتے ہیں.ان مؤرخین کے انداز تحقیق و تحریر سے ظاہر ہے کہ وہ اس موضوع پر کام کرنے والے دیگر جدید
مغربی مؤرخین سے بے حد مختلف ہیں.وہ اپنے عہد اور معتقدات کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ
تھے.اپنی کتب میں انہوں نے بہت سے غیر معمولی اور کافی حد تک ایسے نا قابل یقین واقعات
بھی شامل کیے ہیں جنہیں ہم آج بہت مختلف انداز میں بیان کریں گے.لیکن وہ معاملات کی
پیچیدگی اور سچائی کی باریک اور مہم نوعیت سے کماحقہ آگاہ تھے.وہ کسی ایک نظریہ کی بنیاد پر کسی
دوسرے نظریہ کو ثابت یا واقعہ کی وضاحت نہیں کرتے بلکہ بعض اوقات وہ مختلف طریقہ کار اختیار
کرتے ہیں.وہ ایک ہی روایت کی ایک سے زیادہ معروف صورتیں پیش کر دیتے ہیں اور ان میں
سے
کسی ایک کی درستگی کے بارے میں کوئی رائے نہیں دیتے اور نہ اس ضمن میں قارئین کی رائے کو
متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں.یہ اور بات ہے کہ ہم آج انہیں کن معیارات پر پرکھیں.
Page 358
الذكر المحفوظ
342
اس دور میں جس حد تک ان سے ممکن تھا انہوں نے ہر ایک واقعہ کو انتہائی تفصیل اور ثبوت کے
ساتھ پیش کیا ہے.تاہم بہت سے موقعوں پر وہ اس بات کو واضح بھی کرتے ہیں کہ وہ خود بھی پیش
کردہ واقعے یا ثبوت سے متفق نہیں ہیں.اس سے یہ بات اظہر من الشمس ہو جاتی ہے کہ اس کے
باوجود کہ ان مؤرخین کی پیغمبر اسلام کی ذات مبارکہ سے گہری عقیدت تھی، انہوں نے آپ کی زندگی
کی تفصیلات کو ممکنہ حد تک درست اور ٹھوس دلائل اور شواہد کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کی ہے.( محمد ( ﷺ ) باب دوم صفحہ 59 58 پبلشرز علی پلازہ 3 مزنگ روڈ لاہور )
ہمیں مذکورہ بالا حوالہ میں مصنفہ کی تمام باتوں سے اتفاق ہونا ضروری نہیں.درج کرنے کا مقصد صرف یہ ہے
کہ دیانت دار محققین تسلیم کرتے ہیں کہ اسلامی مؤرخین اور محققین نے کس دیانت داری سے گردش کرنے والی تمام
سچی اور جھوٹی تفصیلات کو اکٹھا کر دیا ہے.اس قسم کی کمزور اور جھوٹی روایات اہل سنت کی طرف بھی منسوب کی گئی ہیں اور اہل تشیع کی طرف بھی مگر
مستشرقین زیادہ تر اہل تشیع کی روایات پر اپنے اعتراضات کی بنیادر رکھتے ہیں.اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل تشیع کی
اکثر روایات کی صحت پر کماحقہ تحقیق نہیں کی گئی.اہل سنت کے مقابل پر اہل تشیع روایات اور تاریخ کی تحقیق میں
بہت ناقص ثابت ہوئے ہیں.اہل تشیع کے سامنے کوئی بھی روایت اہل بیعت یا ائمہ کی طرف منسوب کر کے بیان
کی جائے تو بلا تحقیق فورا لتسلیم کر لیتے اور زیادہ تر جذباتیت کی نظر سے اسے دیکھتے اور غیرت کے نام پر اس کے
بارہ میں یہ سننا بھی گوارا نہیں کرتے کہ یہ روایت بے اصل اور اہل تشیع کی اہل بیعت اور ائمہ سے محبت کا نا جائز
فائدہ اُٹھاتے ہوئے گھڑی گئی ہے.حالانکہ محبت کا صحیح تقاضا تو یہ تھا کہ اہل بیت کے اصل اقوال کی کھوج کی جاتی
اور ان کی طرف منسوب جھوٹی باتیں اُن سے دُور کی جاتیں کیونکہ وہ اُن پاک وجودوں پر الزام ہیں.ان روایات کو گھڑنے کی ایک اور وجہ اصحاب النبی صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے نفرت اور تعصب بنی.وہ روایات
جن میں صحابہ کی ذم ہوتی ان کو بلا تحقیق تسلیم کر لیا جاتا.حضرت علی نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر 127 میں اسی خطرہ کا
اظہار فرماتے ہیں کہ خطرہ ہے کہ محبت میں غلو کی وجہ سے یا نفرت میں شدت کی وجہ سے تم لوگ گمراہ ہو جاؤ گے.چنانچہ تاریخ کے حوالہ سے یہ بات مزید واضح ہو کر سامنے آگئی ہے.اہل سنت کی روایات کے بارہ میں گہری
تحقیقات کی گئیں اور جب بھی ان روایات کی بنیاد پر کوئی غلط نتیجہ نکالنے کی کوشش کی گئی تو اکثر و بیشتر ایسی روایات
کے بارہ میں معلوم ہوا کہ اہل علم پہلے سے ہی اس کا غلط ہونا ثابت کر چکے ہیں.جبکہ اہل تشیع کی روایات عام طور
پر روایت اور درایت کے اصولوں کی پروا کیے بغیر تسلیم کر لی گئی ہیں اور انہیں کتابوں میں جگہ دی گئی ہے جس کی وجہ
سے بہت سے دُشمنانِ اسلام ان روایات پر بنیا درکھ کر اعتراضات کرتے ہیں.جب بھی ایسی روایت کے بارہ
Page 359
حفاظت قرآن کریم پر متفرق اعتراضات
343
میں تحقیق کی جائے تو کچھ پتا نہیں چلتا کہ یہ بات کب کہی گئی اور اس کے راوی کون تھے.یہ درست ہے سنی اور شیعہ اور اسی طرح مختلف فرقوں کے ملا جہالت اور دشمنی میں ایک دوسرے پر قرآن کریم
میں یا تحریف کرنے کے الزامات لگاتے رہتے ہیں مگر وہ بھی عام طور پر مستشرقین والا رویہ ہی اختیار کرتے ہیں
اور تعصب میں اندھے ہو کر جھوٹ بولتے ہیں.یہ ملانوں کا وطیرہ ہے کہ ایک دوسرے الزامات لگانے کے شوق
میں ایسی موشگافیاں کرتے رہتے ہیں اور ان میں سے کچھ سادہ لوح دوسرے فرقوں کے بارہ میں واقعی ایسا سمجھتے
بھی ہیں.ایسے مستند علماء جو یہ اقرار کرتے ہوں پیش کرنے چاہئیں.ہم ثابت کر آئے ہیں کہ ایسی کوئی آیات نہیں جو
درج ہونے سے رہ گئی ہوں یا بعد میں ڈالی گئی ہوں.اگر کوئی ایسی آیت ہے تو دلائل کے ساتھ پیش کرنی چاہیئے.پس قرآن کریم تاریخ مذاہب کی واحد ایسی کتاب ہے جو نزول کے ساتھ ساتھ تحریری اور حفظ ، دونوں طور
سے محفوظ کی گئی اور واحد کتاب ہے جس کے بارہ میں اپنے اور پرائے ، دوست اور دشمن بلا تفریق مذہب وعقیدہ
گواہیاں دیتے چلے آئے ہیں کہ یہ کتاب آج تک انسانی دست برد سے
مکمل طور پر پاک ہے.حضرت عثمان کے
دور تک تو مستشرقین حفاظت قرآن کے موضوع پر اپنی جہالت یا عوام کی عدم واقفیت اور سادہ لوحی کی بنیاد پر
اعتراض یا شبہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں.حضرت عثمان کے دور کے بعد اشاعت قرآن کا ایک ایسا دور
شروع ہوتا ہے جس میں قرآن کریم میں تبدیلی کا کسی قسم کا کوئی شک نہیں کیا جاسکتا.کثرت سے قرآن کریم کے نسخہ جات
تحریر کیے گئے جو حضرت عثمان کے مصحف کی بعینہ نقل تھے.کثرت سے حفاظ پیدا ہوئے اور قرآن کریم کی کتابت،
حفظ اور تلاوت ہر شعبہ میں امت مسلمہ میں بے مثال کام ہوا.کتابت، حفظ اور تلاوت کے شعبوں کو علماء نے
با قاعدہ سائنسی بنیادوں پر استوار کیا.پھر تفسیر اور اخذ معارف کے میدان میں بھی بہت وسیع کام ہو اور بلا مبالغہ
ہزاروں جلدیں لکھی گئیں.ان تمام کاموں میں قرآنی آیات کا کثرت سے اندارج ہو تا تھا اس لیے اس میدان
میں ترقی سے بھی قرآن کریم کی معنوی حفاظت کے ساتھ ساتھ اس کی ظاہری حفاظت کا امر بھی قوی تر ہوتا چلا
گیا.پھر مسلمان سائنس اور دیگر دنیاوی علوم کے میدانوں میں نکلے تو بھی قرآن
کو ہی بنیاد بنایا اور ہر علم کی
وضاحت قرآن کریم سے کرنے کی کوشش کی.حضرت خلیفہ اسیح الثانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:
میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان سب کتابوں سے آیات کو جمع کیا جائے تو ان سے بھی سارا
قرآن جمع ہو جائے گا.مسلمانوں میں قرآن کریم کی خدمت کے لیے دوسرے علوم کی طرف
رجوع کا ایک ضمنی فائدہ یہ بھی ہوا کہ پہلی کتابوں سے تو دنیوی علما کا طبقہ سخت بیزار تھا مگر
مسلمانوں میں سے ان علوم کے ماہر ہمیشہ قرآن مجید کے خادم ہی رہے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں
که قرآن کریم بچے علوم کا دشمن نہیں بلکہ مؤید ہے.“
( تفسیر کبیر جلد چہارم زیر تفسیر آیت سورۃ الحجر 10 صفحہ 17)
Page 360
الذكر المحفوظ
344
قرآن کریم کے قدیم نسخے آج بھی موجود ہیں جو قرآن کریم کی حفاظت کے ناقابل تردید ثبوت اور ایسے گواہ
ہیں جن کو جھٹلایا نہیں جاسکتا.مزید برآں حضرت عثمان کے دور کا ایک نسخہ آج بھی موجود ہے جو کہ 25 ھ میں
تیار کیا گیا.اس مصحف پر لکھا ہوا ہے " هذا ما اجمع عليه جماعة من اصحاب رسول الله صلى
الله عليه و سلم منهم زيد بن ثابت و عبد الله بن زبیر و سعید ابن العاص آگے اور
صحابہ کے نام ہیں.یہ نسخہ تا حیات حضرت عثمان کے پاس رہا پھر حضرت علیؓ کے پاس رہا، پھر حضرت امام حسنؓ کے
پاس رہا.پھر امیر معاویہ کے سپرد ہوا.اس کے بعد اندلس لے جایا گیا.اندلس سے مراکش کے دارالسلطنت
فاس منتقل ہوا اور پھر کسی طرح مدینہ واپس پہنچایا گیا.جنگ عظیم اول میں فخری پاشا گورنر تر کی دیگر تبرکات کے
ساتھ اس
نسخہ کو بھی قسطنطنیہ لے گیا.اب تک وہاں موجود ہے.اس کے متعلق یہ حقائق درج کیے جاچکے ہیں کہ
اس نسخہ کی تیاری کے بعد حضرت ابو بکر کے دور خلافت میں تیار کیا گیا نسخہ مصحف ام قریباً 25 سال تک محفوظ موجود
رہا.مگر کسی نے اس کا مصحف ام سے اختلاف ثابت نہیں کیا.گویا قرآن کریم کے ان نسخہ جات سے لے کر، جو
حضرت رسول
کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے زیر نگرانی تحریری صورت میں محفوظ کیے گئے اور جن کی موجودگی میں
مصحف ام تیار کیا گیا، جسے حضرت ابو بکڑ نے امت کی گواہی سے تیار کیا، آج تک ایک نہ ٹوٹنے والا ایک تو اتر ہے.ابنِ وراق کہتا ہے کہ اکثر محققین یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں تحریف ہوئی ہے.ان محققین کے بارہ میں
ہم دیکھ آئے ہیں کہ یہ دراصل کون لوگ ہیں.اگر یہ کہتے ہیں کہ تحریف ہوئی ہے تو بہت سے مسلمان اور غیر مسلم
محقق ایسے بھی تو ہیں جو کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی.پس دونوں گروہوں میں سے سچا کون
ہے اس کا فیصلہ تو تبھی ہو سکتا ہے کہ جب دونوں گروہوں کے دلائل کا تجزیہ کیا جائے.ایک گروہ کے دلائل کا
مطالعہ تو ہم کر آئے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھ آئے ہیں کہ جو تحریف ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ زیادہ
تر جھوٹ اور دجل سے کام لیتے ہیں اور دلائل کی جگہ قیاسی اور ظنی باتیں پیش کرتے ہیں.اسلام کے بارہ
میں تحقیق کرتے ہوئے دیانت داری کو بالائے طاق رکھتے ہوئے مستند روایات کو یہ کہہ کر رد کر دیتے ہیں کہ یہ
رسول کریم کے بعد سینہ بسینہ منتقل ہوتی رہیں پھر سو سال سے زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد ضبط تحریر میں آئیں.مگر
جب اپنے مفید مطلب کوئی غلط نتیجہ نکالنا چاہتے ہیں تو ایسی غیر مستند اور ضعیف روایات پر اپنے اندازوں کی بنیاد
رکھتے ہیں جنہیں محققین بالاتفاق کمزور اور غلط تسلیم کر چکے ہوتے ہیں.جبکہ محافظت قرآن کریم کے تاریخی پہلو پر
محور کرنے والے بہت سے مغربی محققین اور مستشرقین یہ گواہی دینے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ یہ کتاب بعینہ اسی
حالت میں ہم تک پہنچی ہے جس حالت میں محمد صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے بنی نوع کے سپرد کی تھی.کچھ گواہیاں
گزشتہ میں گزرچکی ہیں.کچھ ہم یہاں ابن وراق کے محققین کے مقابل پر پیش کر دیتے ہیں.
Page 361
حفاظت قرآن کریم پر متفرق اعتراضات
345
حفاظت قرآن کے ضمن میں مستشرقین اور مغربی محققین کی گواہیاں
H.A.R.Gibb کہتے ہیں:
It seems reasonably well established that no material
changes were introduced and that the original form of
Mohammed's discourses were preserved with scrupulous
precision.(H.A.R.Gibb, Mohammedanism, London: Oxford University
Press, 1969, p.50)
یہ ایک نہایت قوی حقیقت ہے کہ قرآن کریم میں کسی قسم کی کوئی تحریف ثابت نہیں کی جاسکی اور
یہ حقیقت بھی بہت قوی ہے کہ محمد (ﷺ) کے بیان فرمودہ الفاظ کو اصل حالت میں مکمل احتیاط کے
ساتھ اب تک محفوظ رکھا گیا ہے.ریورنڈ باسورتھ سمتھ رقم طراز ہیں:
In the Quran we have, beyond all reasonable doubt, the
exact words of Muhammed without subtrection and without
addition.(R.Basworth Smith "Mohammad and Mohammadanism".London
1874, p.15)
جو قرآن کریم آج ہمارے پاس موجود ہے وہ بلا شک و شبہ کسی بھی قسم کی کمی بیشی
کے بغیر بعینہ محمد (ع) کا کلام ہے.ایک دوسری جگہ لکھتے ہیں :
اختلاف قراءت ختم کرتے وقت الفاظ اور اعراب
کو مکہ کی بہترین قراءت پر قائم کر دیا گیا لیکن
یہ بات طے شدہ ہے
محمد ( ﷺ ) کا پیش کردہ اصل متن انتہائی درستی کے ساتھ قائم رکھا گیا.(R.Basworth Smith"Mohammad and Mohammadanism".London
1874, p.165)
اطالوی مستشرقہ وگلیری قرآن کریم کی بے مثال حفاظت کا ذکر کرتے ہوئے رقم طراز ہیں:...the centuries from the day of the delivery until today, and
will remain so, God willing, as long as the universe continues
to exist.(An Interparatation of Islam P: 41)
( قرآن کریم ) اپنے نزول سے لے کر صدیوں کا عرصہ گزرنے کے بعد آج بھی محفوظ ہے
اور آئندہ بھی ان شاء اللہ رہتی دنیا تک محفوظ رہے گا.
Page 362
346
الذكر المحفوظ
دوسری جگہ لکھتی ہیں:
It is to the holy book which has never been altered at the
hands either of its friends or its enemies, by either the learned
or the unlettered, the book that time does not wear out but
which remains just as it was revealed by God to the rough and
simple Apostle, the last of all law-bearing Propherts.(opcit P:87)
یہ وہ مقدس کتاب ہے جو کبھی بھی انسانی دست بُر دکا شکار نہیں ہوئی، نہ اپنوں کے ہاتھوں اور
نہ ہی دُشمنوں کے ہاتھوں، نہ علما کے ہاتھوں اور نہ جہلا کے ہاتھوں.یہ بعینہ ویسی ہے جیسی خدا
کی طرف سے اس نئی معصوم، خاتم النبین ( ﷺ ) پر نازل کی گئی.فلپ کے حتی کہتے ہیں:
The Arabic copy that a Moslem uses today is an exact
replica of a heavenly prototype, dictated word by word to the
Prophet Mohammad.(Islam, A Way of Life P:26)
آج قرآن کریم کا عربی متن اس الہی صحیفہ کی نقل بمطابق اصل ہے جو محمد رسول اللہ
(ع) کو لفظ لفظا لکھوایا گیا تھا.مستشرق John Burton اختلاف قراءت پر بحث کے بعد اپنی تحقیق کے آخر پر لکھتا ہے:
No major differences of doctrines can be constructed on
the basis of the parallel readings based on the Uthmanic
consonantal outline, yet ascribed to mushafs other than his.All the rival readings unquestionably represent one and the
same text.They are substantially agreed in what they
transmit...(John Burton, The Collection of the Qur'an, Cambridge:
Cambridge University Press, 1977, p.171)
یعنی ( حضرت ) عثمان کے مصحف اور دیگر قراء توں والے صحائف کے متن میں کسی قسم کے
اعتقادی اختلاف کی نشان دی نہیں ہوتی.تمام قراء تیں بلاشک وشبہ ایک ہی متن کی نمائندگی
کرتیں اور ایک مضمون بیان کرتی ہیں.مزید کہتا ہے اور گزشتہ سطور میں یہ گواہی گزر بھی چکی ہے:
(The Qur'an as we have it today is) the text which has come
down to us in the form in which it was organized and
approved by the Prophet....What we have today in our hands
Page 363
is the mushaf of Muhammad.347
حفاظت قرآن کریم پر متفرق اعتراضات
(John Burton, The Collection of the Qur'an, Cambridge:
Cambridge University Press, 1977, p.239-40)
ہم تک پہنچنے والا متن بعینہ وہی ہے جو خود نبی کریم ﷺ ) کا مرتبہ اور مصدقہ ہے.چنانچہ
آج ہمارے پاس جو کتاب ہے یہ دراصل مصحف محمدی ہی ہے.یکھنی
ممتاز مستشرق Kenneth Cragg حفظ قرآن پر بحث کرتے ہوئے بھتی ہے
ہیں:
This phenomenon of Qur'anic recital means that the text
has traversed the centuries in an unbroken living sequence of
devotion.It cannot, therefore, be handled as an antiquarian
thing, nor as a historical document out of a distant past.The
fact of hifz (Qur'anic memorization) has made the Qur'an a
present possession through all the lapse of Muslim time and
given it a human currency in every generation, never allowing
its relegation to a bare authority for reference alone.(Kenneth Cragg, The Mind of the Qur'an, London: George Allen
& Unwin, 1973, p.26)
قرآن کریم کے حفظ کا اعجاز یہ ہے کہ متن قرآنِ کریم صدیوں کا سفر طے کرتے ہوئے
انتہائی محبت اور خلوص اور وقف کی روح کے ساتھ ایک تو اتر کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے.لہذا اس
کے ساتھ نہ تو کسی قدیم چیز جیسا سلوک روا رکھنا چاہیے اور نہ ہی اسے محض تاریخی دستاویز سمجھنا
درست ہے.در حقیقت حفظ کی خوبی نے اس کتاب کو مسلم تاریخ کے مختلف ادوار میں زندہ و جاوید
رکھا ہے اور بنی نوع کے ہاتھ میں نسلاً بعد نسل ایک معتبر متاع تھا دی اور کبھی بھی محض غیر اہم
کتابی صورت میں نہیں چھوڑا.Schwally اپنی تحقیق ، جس میں تعصب نمایاں طور پر جھلکتا ہے بیان کرتے ہوئے بمشکل تسلیم کرتا ہے:
"As far as the various pieces of revelation are concerned,
we may be confident, we may be confident that their text has
been generally transmitted exactly as it was found in the
Prophet's legacy"
(Schwally, Geschichte des Qorans, Leipzig: Dieterich'sche
Verlagsbuchhandlung,1909-38, Vol.2, p.120)
جہاں تک ( قرآنی ) وحی کے مختلف حصوں
کا تعلق ہے، ہمیں یہ اعتبار کر لینے میں کوئی حرج
نہیں کہ ان کا متن بالعموم ہم تک اُسی حالت میں پہنچا ہے جیسے نبی کریم ﷺ ) چھوڑ گئے تھے.ویلیئم میور کہتا ہے:
"There is probably no other book in the world which has
Page 364
الذكر المحفوظ
348
remained twelve centuries with so pure a text"
قرآن کریم کے علاوہ) شائد دنیا کے پردے پر اور کوئی ایسی کتاب نہیں جس کا متن بارہ
سو سال گزرنے کے باوجود اپنی اصل حالت میں قائم ہو.مزید کہتا ہے:
We may upon the strongest presumption affirm that every
verse in the Coran is genuine and unaltered composition of
Muhammad Himself.ہم نہایت مضبوط قیاسات کی بنیاد پر یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ قرآن کریم کی ہر آیت
اپنی اصل حالت میں، جس میں محمد (ﷺ) نے لکھا تھا، ہے اور بالکل غیر محرف وغیر مبدل ہے.And conclude with atleast a close approximation to the
verdict of Van Hammer that we hold the Coran to be as surely
Muhammad's words as the Muhammadans held it to be the
word of God.(William Muir, Life of Mohamet, London, 1894, Vol.1,
Introduction)
یعنی اور ہماری اس بحث کا نتیجہ Van Hammer کے اس قول کے قریب ترین ہے کہ
ہمارے پاس وہ قرآن ہے جس کے بارہ میں ہم اتنے ہی یقین سے کہتے ہیں کہ یہ محمد (ﷺ)
کے ہی الفاظ ہیں جتنے یقین سے مسلمان کہتے ہیں کہ یہ خدا کے الفاظ ہیں.Dr.Maurice Bucaille لکھتے ہیں:
The Book contains the Word of God, to the exclusion of
any human additions.Manuscripts dating from the first
century of Islam authenticate today's text, the other form of
authentication being the recitation by heart of the Qur'an, a
practice that has continued unbroken from the time of the
Prophet down to the present day.(The bible The Quran and Science (translation from French by
Alastair D.Pannel and The Ahthor) Under Heading The Quran and
Modern Science Pg 120)
یہ کتاب خدا کا کلام ہے جس میں کوئی انسانی ملونی نہیں، ہمارے پاس محفوظ پہلی صدی کی
تحریرات آج ہمارے پاس موجود متن کو مستند بناتی ہیں ، اور استناد کا دوسرا ذریعہ حفظ قرآن کا
طریق ہے یعنی ایک ایسی عادت مستمرہ جو نبی کریم ) کے دور سے آج تک ایک تواتر کے
ساتھ جاری ہے.
Page 365
349
حفاظت قرآن کریم بر متفرق اعتراضات
نیز کہتے ہیں:
There was absolutely no doubt about it: The text of the
Qur'an we have today is most definitely a text of the period.(opcit)
اس بات میں ذرہ بھی شک نہیں کہ ہمارے پاس قرآن کریم کا وہی متن موجود ہے جو
صلى الله
آپ (ع) کے دور میں تھا.اسی کتاب میں ایک اور جگہ لکھتے ہیں:
They had the advantage of being checked by people who
already knew the text by heart, for they had learned it at the
time of the Revelation itself and had subsequently recited it
constantly.Since then, we know that the text has been
scrupulously preserved, It does not give rise to any problems
of authenticity.(Under Heading "Conclusions" Pg 250-251)
انہیں ( یعنی جن لوگوں کو حضرت ابو بکر نے جمع قرآن کا حکم دیا تھا ) ایک فائدہ یہ بھی
حاصل تھا کہ اُن لوگوں سے تصدیق کروا لیتے تھے جنہوں نے وحی کے نزول کے وقت ہی
اسے حفظ کر لیا تھا اور بار بار اس کی تلاوت کرتے رہتے تھے.ہم جانتے ہیں کہ اس وقت
سے قرآن کریم کا متن بلاشبہ محفوظ ہے اور اس کے استناد پر کوئی سوال نہیں اُٹھتا.In contrast to the Bible, therefore, we are presented with a
text that is none other than the transcript of the Revelation
itself;
بائبل کے بر عکس ہمارے پاس وہ متن موجود ہے جس میں وحی الہی کے علاوہ کوئی اور تحریر
شامل نہیں.اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے ایک بہت مفید بحث پیش کی ہے جس میں وہ قرآن کی حفاظت کے حوالے
سے مفصل اور مدلل گفتگو کرتے ہیں.اور آخر میں پھر یہی نتیجہ پیش کرتے ہیں کہ:
Today's editions of the Qur'an are all faithful reproductions
of the original copies.In the case of the Qur'an, there are no
instances of rewriting or corruption of the text over the course
of time.(The bible The Quran and Science (translation from French by
Alastair D.Pannel and The Ahthor)Under Heading Conclusions
Pg 102)
آج کے دور میں مہیا ہونے والے قرآن کریم کے تمام نسخے اصل متن کی دیانت داری سے
Page 366
الذكر المحفوظ
350
کی گئی نقول ہیں.قرآن کے معاملہ میں اب تک کے شب و روز میں تحریف یا تبدل کا کوئی سراغ
نہیں ملتا.پھر انسائیکلو پیڈیا بریٹینز کا میں درج نولڈ یکے کی یہ شہادت بہت مشہور ہے.زیر لفظ قرآن درج ہے:
Efforts of European scholars to prove the existence of
later interpolations in the Qur'an have faild."
(Encyclopedia Britanica Edition 11 under Heading "Quran")
یورپ کے محققین کی وہ تمام کوششیں جو قرآن میں بعد میں اضافہ جات ثابت کرنے کے
لیے کی گئی تھیں قطعاً نا کام رہی ہیں.ان کے علاوہ بھی بہت سے محققین اور مستشرقین ہیں جو یہ گواہی دیتے چلے آئے ہیں کہ قرآن کریم بلاشبہ محفوظ اور
انسانی دست برد سے بکلی پاک کلام ہے.ان میں میونخ یونیورسٹی کے محققین کی 50 سال کی تحقیق بھی شامل ہے.1 - ( محمد حمید اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم؛ ادارہ اسلامیات لاہور، صفحہ 179 )
2- (Method of preservations of the Quran during the Prophet's
time
(http://www.islam101.com/quran/source_quran.html)
ابن وراق کو چاہیے کہ ان سب اہلِ علم کو سمجھائے کہ قرآنی حفاظت کے موضوع پر اپنی جان اتنی ہلکان کر رہے
ہو.گہری گہری تحقیقات اور لمبی لمبی بحثیں کر کے یہ نتائج اخذ کر رہے ہو کہ قرآن کریم بلا شبہ محفوظ ہے.دل میں
تعصب بھی ہے پھر بھی دلائل کو دیکھ کر محافظت قرآن کریم کی حقیقت کو تسلیم کر رہے ہو.اپنے دل کی جلن اور
حسرتوں کی آگ کو ٹھندا کرنے کے لیے آسان راہ تو یہی ہے کہ کہہ دو کہ میرا خیال اور اندازہ ہے کہ قرآن کریم میں
ضرور تحریف ہوئی ہے.کیوں گہری تحقیقات کی مشقت اُٹھاتے ہو؟
محافظت کے حوالہ سے قرآن کریم کا دیگر مذاہب کے صحائف کے ساتھ موازنہ کیا جائے تو دوسرے صحائف میں
ہمیں جگہ جگہ انسانی دست برد کی کارستانیاں نظر آتی ہیں اور تحریف اور تبدل کے نمونے ملتے ہیں.دیگر مذہبی صحائف
خاص کر بائبل کو جب اس نظر سے دیکھتے ہیں تو اس دور میں بھی جبکہ ہر طرف بائبل پھیلی ہوئی ہے، انتہائی دیدہ دلیری
سے تحریف کی جاتی ہے کہ ایک نسل ہی اس تحریف کے نمونے دیکھ لیتی ہے اور صدیوں کا انتظار نہیں کرنا پڑتا.حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں:.یہودیوں کو توریت کے لیے کہا کہ اس میں تحریف و تبدیل نہ کرنا اور بڑی بڑی تاکیدیں ان
کو اس بات کی کی گئیں.لیکن کم بخت یہودیوں نے اس میں تحریف کر دی.اس کے بالمقابل
مسلمانوں کو کہا إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحفِظُونَ.(الحجر:۱۰) پھر دیکھ لوکہ کیسی
حفاظت اس نے فرمائی.ایک لفظ اور نقطہ تک پس و پیش نہ ہوا.اور کوئی ایسا نہ کر سکا کہ اس میں
Page 367
حفاظت قرآن کریم پر متفرق اعتراضات
351
تحریف و تبدیل کرتا.صاف ظاہر ہے کہ جو کام خدا کے ہاتھ سے ہوتا ہے وہ بڑا ہی بابرکت ہوتا ہے.( ملفوظات جلد سوم.صفحہ 405 مطبوعہ ربوہ )
ایک اور جگہ فرماتے ہیں:.اگر تمام دنیا میں تلاش کریں تو قرآن مجید کی طرح خالص اور محفوظ کلام الہی کبھی نہیں مل
سکتا.بالکل محفوظ اور دوسروں کی دستبرد سے پاک کلام تو صرف قرآن مجید ہی ہے.روئے
زمین پر ایک بھی ایسی کتاب نہیں جس کی حفاظت کا وعدہ خود اللہ کریم نے کیا ہو اور جس میں انا
نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِكَرَوَ إِنَّا لَهُ لَحْفِظُونَ (الحجر: ۱۰) کا پُر زور متحد یا نہ دعولی موجود ہو.( ملفوظات جلد 5 صفحہ 338 مطبوعہ ربوہ)
قرآن کریم وہ یقینی اور قطعی کلامِ الہی ہے جس میں انسان
کا ایک نقطہ یا ایک شعشہ تک دخل نہیں
اور وہ اپنے الفاظ اور معانی کے ساتھ خدا تعالیٰ کا ہی کلام ہے اور کسی فرقہ اسلام کو اس کے ماننے سے
چارہ نہیں.اس کی ایک ایک آیت اعلیٰ درجہ کا تواتر اپنے ساتھ رکھتی ہے.وہ وحی متلو ہے جس کے
حرف حرف گنے ہوئے ہیں.وہ باعث اپنے اعجاز کے بھی تبدیل اور تحریف سے محفوظ ہے.(ازالہ اوہام.روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 384 )
اب تک ہم قرآن کریم کی حفاظت کے پہلو کا تاریخی اور منطقی نقطہ نظر مطالعہ کرتے ہوئے اس نتیجہ پر پہنچے
ہیں کہ قرآن کریم میں چھوٹی یا بڑی کسی بھی قسم کی کوئی تبدیلی راہ نہیں پاسکی.قرآن کریم کا اصل متن تمام تر حفاظت
کے ساتھ بعینہ اسی حالت میں ہم تک پہنچا ہے جس حالت میں یہ متن رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم پر نازل ہوا اور
جس حالت میں آپ نے صحابہ کے سپرد کیا.اس ضمن میں ابن وراق کے اُٹھا گئے اعتراضات کی قلعی بھی کھل گئی.یہ ذکر گزر چکا ہے کہ اس کتاب کا مقصد عام قاری کے دل میں حفاظت قرآن کے بارے میں شک پیدا
کرنا ہے.چنانچہ ابن وراق مذکورہ بالا اعتراض کے ذریعے یہ تاثر دینے کی کوشش کرتا ہے کہ گویا حفاظت قرآن
کے معاملہ میں امت مسلمہ میں بھی شکوک و شبہات ہیں اور ابتدائی زمانہ اسلام سے لے کر آج تک مسلمان ان
شکوک میں گرفتار ہیں.اب بھی مسلمانوں میں دو مختلف قرآن رائج ہیں اور اہل تشیع کو بھی قرآن کی حفاظت کے
معاملہ میں شک ہے.گویا قاری کو یہ سمجھایا جارہا ہے کہ اگر تمہیں کوئی شک نہیں ہے تو یہ حیرت کی بات ہے.تمہیں کچھ خبر ہی نہیں کہ محافظت قرآن کریم کے بارہ میں سارا عالم اسلام تو شکوک وشبہات کا شکار ہے اور تم
بھولے بادشاہ اسے محفوظ سمجھے بیٹھے ہو.
Page 368
الذكر المحفوظ
352
حفظ قرآن کریم پر اعتراض
Both Hugronje and Gulliaume point to the mindless
children are forced to learn either parts of or the
way
entire Koran (some 6,200 odd verses) by heart at the
expense of teaching children critical thought: "[The
Children] accomplish this prodigious feat at the expense
of their reasoning faculty, for often their minds are so
stretched by te effort of memory that they are little good
for serious thought.(Ibn Warraq: Why I am Not A Muslim, Prometheus Books, New
York, 1995, under heading; The Koran: Pg 105)
ہم آواز معترضین کے حوالہ سے درج کیے جانے والے ابن وراق کے اس اعتراض کا لب لباب یہ ہے کہ سارا
قرآن کریم فضول طریق پر بچوں
کو زبانی یاد کروایا جاتا ہے.اس کوشش سے بچے کا ذہن متاثر ہوتا ہے اور وہ کسی
قابل ذکر سنجیدہ کام کے قابل نہیں رہتا اور معاشرے میں مفید وجود بننے کی بجائے ناکارہ وجود بن کر رہ جاتا ہے.یہ اعتراض بھی اندھے حسد اور تعصب کا نتیجہ ہے.یہ ایک جانی مانی حقیقت ہے کہ انسانی قومی ورزش اور مشق
سے مضبوط اور قوی ہوتے ہیں اور جتنا استعمال کیا جائے ان کی صلاحیت میں اتنا ہی اضافہ ہوتا ہے.ہم عربوں
کے حافظہ کا ذکر کر آئے ہیں.اس غیر معمولی حافظہ کی ایک بڑی وجہ تحریر کا رواج نہ ہونے کی وجہ سے حافظہ پر زیادہ
انحصار اور حفظ کرنے کیا زیادہ مشق تھی.اس دور میں عربوں کو ہزاروں کی تعداد میں نسب نامے اور اشعار اور ادب پارے
یاد ہوتے تھے.جوں جوں لکھنے کا رواج عام ہوتا گیا تو عربوں نے بھی بجائے حافظہ پر زور دینے کے تحریر پر زور
دینا شروع کر دیا اس لیے حافظہ پہلے جیسا نہ رہا.پس ابنِ وراق برائے اعتراض ایک ایسی بات کر رہا ہے جو قوانین قدرت کے بھی خلاف ہے اور صدیوں
کے جانے مانے حقائق کو بھی جھٹلا رہی ہے.وہ قوم جسے ہزاروں ہزار شعر یاد ہوتے ، جو نسب ناموں
کو از بررکھتی،
جسے اپنی صدیوں کی تاریخ حفظ ہوتی، کیا قرآن کریم جیسی ایک با ربط ، منتظم، اور آسانی سے یاد ہو جانے والی کتاب
سے اس کی ذہنی صلاحیتوں پر اثر پڑنا تھا؟ قوت حفظ کی زیادہ مشق سے ہی تو اُن کا حافظہ غیر معمولی ہوا تھا.اور
قرآن کریم جیسے مرتب کلام کے حفظ سے تو بہت صحت مند مشق ہوتی ہے اور حافظہ کی صلاحیت بہت بڑھ جاتی
ہے.حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں:
تمام قومی انسانیہ کا قیام اور بقا محنت اور ورزش پر ہی موقوف ہے.اگر انسان ہمیشہ آنکھ بند
رکھے اور کبھی اس سے دیکھنے کا کام نہ لے تو جیسا کہ تجارب طبیہ سے ثابت ہو گیا ہے)
Page 369
حفاظت قرآن کریم پر متفرق اعتراضات
353
تھوڑے ہی دنوں کے بعد اندھا ہو جائے گا اور اگر کان بند رکھے تو بہرہ ہو جائے گا.اور اگر
ہاتھ پاؤں حرکت سے بند رکھے تو آخر یہ نتیجہ ہوگا کہ ان میں نہ حس باقی رہے گی اور نہ حرکت.اسی طرح اگر قوت حافظہ سے
کبھی کام نہ لے تو حافظہ میں فتور پڑے گا.اور اگر قوت متفکرہ کو بیکار
چھوڑ دے تو وہ بھی گھٹتے گھٹتے کالعدم ہو جائے گی.سو یہ اس کا فضل و کرم ہے کہ اس نے بندوں
کو اس طریقہ پر چلانا چاہا جس پر ان کی قوت نظریہ کا کمال موقوف ہے.(براہین احمد یہ روحانی خزائن جلد اول صفحہ 507 تا 509 ایڈیشن اول صفحہ 424 تا 426)
پس انسانی قومی کو تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح تخلیق کیا ہے کہ جن قومی کو زیادہ استعمال میں لایا جاتا ہے وہ
طاقتور ہوتے چلے جاتے ہیں اور جن قومی کو استعمال میں نہ لایا جائے وہ کمزور تر ہوتے جاتے ہیں.اسی لیے
از منہ گزشتہ میں عمومی طور پر بنی نوع آج کے دور کے انسان سے زیادہ مضبوط اور صحت مند تھے.اس کی ایک وجہ
اپنے قویٰ کا زیادہ استعمال تھا.اسی طرح بنی نوع عمومی طور پر ، موجودہ دور کے ترقی یافتہ طبقہ میں پلنے بڑھنے
والے انسان سے زیادہ اچھے حافظہ کے مالک تھے.اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے ازمنہ گزشتہ سے حوالے تلاش
کرنے کی ضرورت نہیں.کسی ایسے بچے سے جو روایتی انداز میں حساب کتاب کا عادی ہو کوئی حسابی جمع تفریق
کروا کر دیکھیں تو وہ اس بچے کی نسبت بہت جلد کرلے گا جو کیلکو لیٹ اور کمپیوٹر وغیرہ کی مدد حاصل کرنے کا عادی
ہے.اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک بچہ روایتی طور پر حسابی سوالات حل کرنے کے لیے ذہن سے کام لیتا ہے اور اس
مشق سے اس کا ذہن حساب کتاب میں
تیز ہو جاتا ہے.لیکن ایک دوسرا بچہ جو کسی ایسے معاشرہ کا فرد ہے جہاں
کیلکولیٹ اور کمپیوٹر کا رواج ہے تو وہ بجائے ذہن استعمال کرنے کے فوراً کسی حسابی آلے کی مدد سے سوال حل کرتا
ہے.گوکیلکو لیڑ سے حل کرنے کی رفتار عام رفتار کی نسبت تیز ہوتی ہے مگر اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ ذہن کام کے
اتنا قابل نہیں رہتا جتنا کہ اس بچے کا جو کیلکولیٹر یا کمپیوٹر کی بجائے اپنے ذہن کا استعمال کرتا ہے.اسی طرح عمومی
طور پر مزدور پیشہ افراد ظاہری طور پر ان افراد سے زیادہ مضبوط اور صحت مند ہوتے ہیں جو دفتری کام کرتے ہیں.پس اب ابن وراق بیچارے نے قرآن کریم کی دشمنی اور بغض میں قوانین قدرت کو بدلنے کا بیڑہ اُٹھا لیا ہے تو
اس کی عقل پر ماتم کرنے کے سوا اور کیا کیا جاسکتا ہے؟ تعصب اور بغض میں اتنا اندھا ہو رہا ہے اور دل میں ایسی
آگ لگی ہوئی ہے کہ بجھنے کو ہی نہیں آرہی.اس غم میں جلتا جارہا ہے کہ قرآن کریم کی حفاظت کے لیے کیوں اس
درجہ بے مثل اقدام کیے گئے کہ کوئی شک ہی نہیں رہنے دیا؟ کیوں نہ قرآن کو نزول کے ساتھ ہی ختم کر دیا گیا؟
محافظت قرآن شریف کی عدیم النظیر حقیقت نے اس نادان دشمن بدطینت کو پاگل کر دیا ہے.اب کچھ بس نہیں
چل رہا تو دل کی آگ بجھانے کے لیے قوانین قدرت کو جھٹلانا شروع کر دیا ہے؟ اب کون اسے سمجھائے کہ
Page 370
الذكر المحفوظ
354
میاں قرآن کریم ہر لحاظ سے قوانین فطرت اور قوانین کے قدرت کے عین مطابق ہے.اس
کی تعلیم بھی اور اس
کی حفاظت کے انتظامات بھی.پس اگر کائنات میں جاری اصولوں کو مانو گے تو قرآن کریم کو بھی ماننا پڑے گا.نہیں تو اپنی کوئی الگ ہی دُنیا بسانی پڑے گی کیونکہ تمہاری کیا کسی بھی انسان کی مجال نہیں کہ خدا تعالیٰ کے بنائے
ہوئے ان قوانین میں کوئی ادنی سا رخنہ بھی پیدا کر سکو.اب خدا تعالیٰ تمہارے دل میں لگی بغض اور نفرت کی آگ
بجھانے کے لیے اپنے لاکھوں سال سے جاری قوانین کو تو نہیں بدل سکتا.پس اگر توفیق ہے تو اپنی ہی کوئی دُنیا بسا
لو.قرآن
کریم تعلیم اور حفاظت کے ذرائع ہر لحاظ سے قوانین قدرت اور قوانین فطرت سے ایسے مطابقت رکھتا ہے
کہ ان کو الگ کیا ہی نہیں جا سکتا اور ایسا کیوں نہ ہو ؟ قرآن اسی خالق کا ہی تو کلام ہے جس کی تخلیق سیہ کا ئنات ہے!
علاوہ ازیں جب یہ ثابت ہو چکا ہے کہ قرآن کریم خدا تعالیٰ کا کلام ہے تو اب ہم یہ سوال پوچھنے کے بھی حق
دار ہیں کیا انسانی ذہن خدا تعالیٰ نے تخلیق نہیں کیا؟ کیا وہ انسانی ذہن کی ساخت ایسی نہیں بنا سکتا کہ اس کے کلام
کو حفظ کرنا ذہنی قومی کے لیے آسان اور فائدہ مند ہو جائے؟
پھرا بن وراق کا یہ کہنا تاریخی حقائق کے بھی خلاف ہے کہ قرآن کریم حفظ کرنے سے ذہنی قومی متاثر ہوتے
ہیں.تاریخ بتاتی ہے کہ قرآن کریم کے حافظ کبھی بھی قرآن حفظ کرنے کی وجہ سے دوسرے انسانوں سے پیچھے
ار ہے.کیا ابن وراق نہیں جانتا کہ سب سے پہلے حافظ قرآن خود رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم تھے.کیا
آپ نے دُنیا میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی ؟ آج جو آگ ابن وراق کے دل میں لگی ہوئی ہے کیا اس کی وجہ وہ
عظیم الشان انقلاب نہیں جس کے تار رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی انگلیوں میں ہیں.ایک ایسا انقلاب
برپا کیا کہ ہر دور میں ابن وراق کی تماش کے بدنصیب پیدا ہوتے رہے اور اس پاکیزہ انقلاب کے اثرات ختم
کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے حسرتناک اور نامراد انجام کو پہنچتے رہے.اگر ابن وراق کی یہ بات
درست ہے تو پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کس طرح یہ عظیم الشان تبدیلی پیدا کر گئے ؟ قرآن کریم حفظ
کرنے کا ذہنی صلاحیتوں پر اگر کوئی بداثر ہو سکتا تھا تو سب سے پہلے آپ کو اس کا شکار ہونا چاہیے تھا.آپ کی
پیدا کردہ تبدیلی کس شان کی ہے اس بارہ میں آپ کے غلام کامل حضرت
مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں:
وہ زمانہ کہ جس میں آنحضرت مبعوث ہوئے حقیقت میں ایسا زمانہ تھا کہ جس کی حالت
موجودہ ایک بزرگ اور عظیم القدر مصلح ربانی اور ہادی آسمانی کی شدید محتاج تھی اور جو تعلیم دی گئی
وہ بھی واقعہ میں سچی اور ایسی تھی کہ جس کی نہایت ضرورت تھی اور ان تمام امور کی جامع تھی کہ
جس سے تمام ضرورتیں زمانہ کی پوری ہوتی تھیں اور پھر اس تعلیم نے اثر بھی ایسا کر دکھایا کہ
لاکھوں دلوں کو حق اور راستی کی طرف
کھینچ لائی اور لاکھوں سینوں پر لا الہ الا اللہ کا نقش جما دیا
Page 371
حفاظت قرآن کریم پر متفرق اعتراضات
355
اور جو نبوت کی علت غائی ہوتی ہے یعنی تعلیم اصول نجات کے اس کو ایسا کمال تک پہنچایا جوکسی
دوسرے نبی کے ہاتھ سے وہ کمال کسی زمانہ میں ہم نہیں پہنچا.(براہین احمدیہ ، روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 112 113 ایڈیشن اول صفحہ 120 121 )
اور پھر غیر بھی اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں.مشہور فرانسیسی شاعر اور مفکر LaMartin نے آنحضور صلی اللہ
علیہ والہ وسلم کی بے پناہ اعلیٰ ذہنی اور دماغی صلاحیتوں کو کتنا خوبصورت خراج تحسین پیش کیا ہے:
Philosopher, orator, apostle, legislator, warrior,
conqueror of ideas, restorer of rational dogmas, of a cult
without images, the founder of twenty terrestrial
empires and of one spiritual empire, that is Muhammad.As regards all standards by which human greatness may
be measured we may well ask, is there any man greater
than he.Lamartine: Historie de la Turquie, Pari 1854, vol.2, pp.276-277.فلاسفر، دانش ور، رسول ، مقتن ، جنگجو، دلوں کو تسخیر کرنے والا ، دین کو منطقی بنیادوں پر استوار
کرنے والا، ایک بت شکن مذہب کا بانی ، ایک روحانی اور ہمیں دُنیاوی سلطنتوں کا بانی.یہ ہے
محمد (صلی اللہ علیہ وسلم ).ان تمام پیمانوں کی رو سے جن سے کسی بھی انسان کی عظمت کو ماپا
جا سکتا ہے ہم یہ پوچھتے ہیں کہ کیا محمد (ﷺ) سے بڑھ کر بھی کوئی شخص عظیم ہو سکتا ہے؟
مائیکل ہارٹ نے اپنی مشہور زمانہ کتاب میں ان ایک سو افراد کا ذکر کیا ہے جنہوں نے انسانی تاریخ
میں انقلابی کارنامے سرانجام دیے.اس کتاب میں سب سے بڑی انقلاب انگیز شخصیت کے طور پر وہ
حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے :
My choice of Muhammad to lead the list of the
world's most influential persons may surprise some
readers and may be questioned by others, but he was the
only man in history who was supremely successful on
both the religious and secular level.Of humble origins, Muhammad founded and
promulgated one of the world's great religions, and
became an immensely effective political leader.Today,
thirteen centuries after his death, his influence is still
powerful and pervasive.The majority of the persons in this book had
advantage of being born and raised in centers of
civilization, highly cultured or politically pivotal
Page 372
356
الذكر المحفوظ
year
nations.Muhammad, however was born in the
570,......at that time a backward area of the world, far
from the centers of trade, art, and learning.The Bedouin tribesmen of arabia had a reputation as
fierce warriors.But their number was small, and
plagued by disunity and interecine warfare, they had
been no match for the larger armies of the kingdoms in
the settled agricultural areas to the north.However,
unified by muhammad for the first time in history, and
inspired by thier fervent belief in the one true God, these
small Arab armies now embarked upon one of the most
astonishing series of conquests in human history.......it may initially seem strange that Muhammad
has been ranked higher than Jesus.There are two
principal reasons for that decision.First, Muhammad
played a far more important role in the development of
Islam than Jesus did in the development of
Christianity....Muhammad, however, was responsible for both the
theology of Islam and its main ethical and moral
principles.In addition, he played the key role in
proselytizing the new faith, and establishing the
religious practices of Islam.(Michael H.Hart:"The 100: A Ranking of the Most Influential
Person in History", New York: Hare Publishing Company, Inc.,
1987.p.33-40)
ترجمہ: دُنیا کی عظیم اور محور گن شخصیات کے تذکرہ میں محمد (ﷺ) کا نام سر فہرست رکھنے
میں شائد بعض قارئین کو حیرت ہو اور کچھ کو اعتراض بھی.لیکن میں پورے وثوق سے کہہ سکتا
ہوں کہ حضرت محمد (ﷺ) تاریخ عالم میں واحد ہستی ہیں جو مذہبی اور دنیاوی دونوں محاذوں پر
یکساں کامیاب و کامران رہے.انہوں نے نہایت عاجزانہ طور پر اپنی مساعی کا آغاز کیا لیکن
نہایت مؤثر سیاسی قائد اور مذہبی پیشوا ثابت ہوئے ، آپ کی وفات پر تیرہ سو سال گذر جانے
کے باوجود آپ کی قوت قدسیہ کے اثرات آج بھی پوری آب و تاب کے ساتھ قائم ہیں.اس
کتاب میں شامل افراد کو یہ برتری حاصل ہے کہ وہ دُنیا کی مہذب اور متمدن، اعلی تعلیم یافتہ اور
سیاسی طور پر مستحکام اقوام میں پرورش پانے والے افراد تھے.ان کے برعکس حضرت محمد (ﷺ)
جنوبی عرب میں 570ء میں پیدا ہوئے جو کہ اس وقت تجارت ، علوم وفنون کے مراکز سے بہت
دور، دنیا کا ایک انتہائی دقیانوسی گوشہ تھا.
Page 373
حفاظت قرآن کریم پر متفرق اعتراضات
357
عرب کے بدو قبائلی تند خو جنگجوؤں کی حیثیت سے جانے جاتے تھے.باوجود یکہ وہ تعداد
میں کم ، پراگندہ، جدید آداب جنگ سے ناواقف تھے اور شمالی زرعی علاقوں میں قائم وسیع
بادشاہتوں کی افواج سے ان کی کوئی برابری نہیں تھی.تاہم تاریخ میں پہلی بار آنحضرت (ع)
نے انہیں یکجا کیا اور وہ سب بچے خدائے واحد و یگانہ پر ایمان لے آئے جس کے بعد اتنی مختصر
سی عرب افواج نے انسانی تاریخ میں فتوحات کا ایک حیران کن سلسلہ قائم کر دیا...اولاً تو یہ بات ہی نہایت حیران کن ہوگی کہ میں نے حضرت محمد (ﷺ) کو حضرت عیسی
سے بلند مرتبہ ظاہر کیا ہے لیکن میرے پاس اس فیصلہ کے لیے دو اصولی وجوہ ہیں :
پہلی وجہ یہ ہے کہ حضرت محمد (ﷺ) نے ترویج و فروغ اسلام میں جو کلیدی کردار ادا کیا ہے وہ
حضرت عیسی کے اس کردار سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے جو انہوں نے عیسائیت کی ترویج میں ادا کیا.حضرت محمد (ﷺ) نے نہ صرف پوری ذمہ داری کے ساتھ اسلام کے بنیادی عقیدہ،
عقیدہ تو حید کو قائم کیا اور دیگر بنیادی اخلاقی ضوابط کی تعیین بھی فرمائی بلکہ آپ نے اس عقیدہ
کی دعوت
و تبلیغ میں بھی کلیدی کردارادا کیا اور اسلامی عبادات کی کماحقہ توضیح کی.Edward Gibbon حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی بے پناہ دماغی اور ذہنی صلاحیتوں کا ان
الفاظ میں اعتراف کرتا ہے:
"His (i.e., Muhammad's) memory was capacious and
retentive, his wit easy and social, his imagination
sublime, his judgment clear, rapid and decisive.He
possessed the courage of both thought and action; and...the first idea which he entertained of his divine mission
bears the stamp of an original and superior genius."
(Edward Gibbon: The History of the Decline and Fall of the
Roman Empire, John Murray, Albemarle St.London 1855, vol.6,
p.335.)
یعنی آپ
کا حافظہ وسیع اور تیز تر ، آپ کا فلسفہ آسان اور عام فہم، آپ
کا تصور اعلیٰ واکمل ،
آپ کا فیصلہ بالکل صاف اور واضح ، تیز اور درست، آپ کو قول اور فعل دونوں کی جرات
یکساں عطا کی گئی تھی اور...اپنے الوہی مشن کے بارہ میں پہلا نظریہ جو آپ نے قائم کیا وہ
ایک حقیقی اور بلند تر سوچ کی حامل ہستی کی طرف سے ہونے کا ثبوت اپنے اندر رکھتا تھا.پھرا بن وراق کے اس اعتراض کی دھجیاں بھی نہیں ملتیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم
کے وصال کے بعد خدا تعالیٰ نے جن خلفاء راشدین کے ذریعہ تمکین دین کی وہ سب بھی حافظ قرآن تھے.اگر
Page 374
الذكر المحفوظ
358
صرف حفاظت قرآن کے حوالہ سے ہی دیکھا جائے تو انہوں نے اپنے آقا و مطاع پر نازل ہونے والے کلام کی
حفاظت کے لیے اپنے آقا کی پیروی میں ایسے ایسے غیر معمولی اقدامات کیے کہ ابن وراق جیسے کتنے مخالفین ہیں
جو صدیوں کوششیں کرنے کے بعد بھی قرآن کریم کی حفاظت کے میدان میں اپنے تمام تر بُرے اور کریہہ
ارادوں کے ساتھ ناکام و نامراد ہوتے چلے جارہے ہیں.انہی خلفا رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں متبعین
اسلام نے حیرت انگیز طور پر معلوم دنیا کا بڑا حصہ انتہائی کم وقت میں معجزانہ طور پر فتح کر لیا تھا.پس اگر حفظ سے
ذہن پر بُرا اثر پڑتا ہے تو پھر یہ حفاظ کس طرح دُنیا سے آگے نکل گئے ؟ ان فاتحین نے صرف غلبہ ہی حاصل نہ کیا
بلکہ مفتوح علاقوں میں تہذیب و تمدن کی بنیاد ڈالی اور علوم وفنون کو ترقی دی.صرف یہ لوگ ہی حافظ قرآن ہی نہ
تھے بلکہ اسلامی افواج کی کثیر تعداد بھی حفاظ پر ہی مشتمل ہوتی تھی.چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی
وفات کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جب جھوٹے مدعیان نبوت سے برسر پیکار ہونا پڑا تو جنگ یمامہ میں لشکر
اسلام کے شہداء میں صرف حفاظ کی تعداد ہی 700 تک جا پہنچی تھی (عد (عمدة القاري جزء 20 كتاب فضائل القرآن
باب جمع القرآن ص 16) یہ فتح نصیب قوم بقول ابن وراق کے اُن لوگوں پر مشتمل ہوتی تھی جن کی ذہنی صلاحیتیں
حفظ قرآن کے نتیجہ میں کند ہو چکیں تھیں.لاحول و لا قوة الا بالله!
حضرت عمرؓ کے دور خلافت میں اسلام کی بیمثال کامیابیاں دیکھ کر دنیا آج بھی انگشت بدنداں ہے.نافع بن
عبد الحارث حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو عسفان میں ملے.حضرت عمرؓ نے انہیں اہل مکہ کا والی مقرر کیا ہوا
تھا.اس نے حضرت عمر کو سلام کیا.حضرت عمرؓ نے اس سے دریافت کیا.تم نے وادی مکہ میں اپنا قائم مقام کس کو
مقرر کیا.نافع نے عرض کیا کہ میں نے ابنِ ابزی کو اپنا قائم مقام مقرر کیا ہے.حضرت عمرؓ نے دریافت فرمایا.ابنِ
ابزلی کون ہے؟ نافع نے عرض کیا.اے امیر المومنین ! وہ حافظ قرآن اور علم الفرائض کا ماہر ہے.اس پر عمر رضی اللہ
عنہ نے فرمایا کہ تمہارا فیصلہ ٹھیک ہے.(الدار سی کتاب فضائل القرآن باب ان الله يرفع بهذا القرآن اقواما
آخرین ) یہی تو وہ درست فیصلے تھے جن کی وجہ سے غیر معمولی فتوحات نصیب ہوئیں.پھر ان فاتحین نے علمی میدان میں ایسے ایسے کار ہائے نمایاں سرانجام دیے کہ جدید علوم کے جدا مجد مسلمان
ہی کہلائے.کیا ذہن ناکارہ ہوں تو علمی فتوحات حاصل ہوتی ہیں؟ اس وقت جب اسلام اپنے عروج پر تھا یورپ
نے کونسی بائبل حفظ کر رکھی تھی کہ ذہن کند تھے اور جہالت کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے.قرآن کریم
ويضع
کی برکات سے عربوں نے کیا کیا حیرت انگیز انقلاب پیدا کیے، غیروں کی زبان سے ان کا ذکر سنیں:
The rise of Islam is perhaps the most amazing event
in human history.Springing from a land and a people
alike previously negligible, Islam spread within a
century over half the earth, shattering great empires,
Page 375
359
حفاظت قرآن کریم بر متفرق اعتراضات
overthrowing long-established religions, remolding the
souls of races, and building up a whole new world - the
world of Islam........For the first three centuries of its existence (circ.C.E.650-1000) the realm of Islam was the most civilized and
progressive portion of the world.Studded with splendid cities, gracious mosques, and
quiet universities where the wisdom of the ancient
world was preserved and appreciated, the Moslem
world offered a striking contrast to the Christian West,
then sunk in the night of the Dark Ages."
(A.M.Lothrop Stoddard: The New World of Islam, London 1932,
pp.1-3)
اسلام کا عروج انسانی تاریخ کا شائد سب سے زیادہ حیران کن واقعہ ہے.اسلام ایک
دور افتادہ سرزمین اور معمولی پسماندہ لوگوں سے پھوٹا اور دُنیا کی بڑی بڑی اور نامور سلطنتوں
ایوانوں میں زلزلہ بپا کرتے ہوئے، لمبے عرصہ سے قائم مذاہب کو پچھاڑتے ہوئے ، اقوام کی
تعمیر نو کرتے ہوئے محض ایک سو سال کے قلیل عرصہ میں ایک جہان
نو کی تعمیر کرتے ہوئے جو کہ
اسلام کا جہان تھا، نصف سے زائد دُنیا فتح کر چکا تھا..ابتدائی تین صدیوں میں اسلامی سلطنت دُنیا کا سب سے مہذب اور ترقی یافتہ حصہ تھا.عالی شان شہروں سے مزین ، پُر وقار مساجد اور ایسی پرسکون یونیورسٹیاں، جہاں زمانہ قدیم
کے علوم نہ صرف محفوظ رکھے جاتے بلکہ قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے.مسلمان دنیا عیسائی مغرب سے
ایک بالکل برعکس نظارہ پیش کرتی تھی جو کہ اس وقت جہالت کی گھٹاٹوپ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا.ابن وراق کو کیا نظر آئے گا قاری خود سمجھ لے کہ قرآن کریم حفظ کرنے والی دہنی طور پر نا کا رہ اقوام اس شان و شوکت
کو کیسے پائیں ؟ اور یہ محض تھے نہیں بلکہ یہی سونے آج بھی ملتے ہیں.امام جماعت احمد یہ حضرت حکیم مولوی
نورالدین صاحب خلیفہ اسیح الاول رضی اللہ عنہ اور حضرت مرزا ناصر احمد صاحب خلیفہ اسیح الثالث رحمہ اللہ
جنہوں نے اپنے دور خلافت میں جماعت کو تمام تر خطرات سے نکالتے ہوئے ترقی کی راہ پر گامزن رکھا، لشکرِ
اسلام کے یہ فتح نصیب شہسوار حافظ قرآن بھی تھے.ہم نے وہ ہستیاں بطور نمونہ کے پیش کر دی ہیں جن کے ہاتھ میں خدا تعالیٰ نے مختلف ادوار میں اسلام کی
کلید فتح و ظفر تھمائی اور یہ وہی ہستیاں ہیں جو ابن وراق کو اور اس جیسے دجل اور مکر سے کام لینے والے دیگر مخالفین
اسلام کو شکست فاش دیتی چلی آئی ہیں.کیا ابن وراق اور اس کی قماش کے یہ لوگ عقل مند نہیں تھے ؟ بخدا ان کی
Page 376
الذكر المحفوظ
360
مکاریاں اور عیاریاں دیکھ معلوم ہوتا ہے کہ بہت عمدہ ذہنی صلاحیتوں کو اسلام دشمنی اور تعصب کی راہ میں برباد
کرتے رہے تھے.پس ان عیار دماغوں کے دانت ہر میدان میں کھٹے کرنے والے یہ حافظ قرآن لیڈ ر اس بات
کا ایک نا قابل تردید ثبوت ہیں کہ حفظ قرآن کریم سے انسانی ذہن کو مزید جلا ملتی ہے.اگر کوئی بُرا اثر پڑا ہے تو
حفظ قرآن کے خدائی اہتمام سے مخالفین اسلام اور مخالفین قرآن کے ذہنوں پر پڑا ہے اور اس غم میں پاگل ہوئے
جارہے ہیں کہ یہ عدیم النظیر ذریعہ محفاظت قرآن کریم کو نصیب ہی کیوں ہو! حفاظت قرآن کے باب میں حفظ قرآن
کا باب تو ایسا باب ہے کہ اس کے سامنے کسی انسان کا کچھ بس نہیں چلتا.کیا ان حافظ قرآن ہستیوں کے ہاتھوں دین اسلام کی اس درجہ شوکت و تمکنت کو دیکھ کر، اور پھر خدمت اسلام
کے جہاد میں ان لوگوں کا کردار دیکھ کر کوئی شخص یہ تسلیم کر سکتا ہے کہ قرآن کریم حفظ کرنے والے کا ذہن کند
ہو جاتا ہے اور وہ کسی بڑے کام کے قابل نہیں رہتا ؟ آدھی دنیا فتح کرنا بڑا کام نہیں ؟ اور صرف ظاہری غلبہ نہیں
بلکہ من موہنا، دلوں
کو تسخیر کرنا کیا یہ بڑا کام نہیں ؟ کیا مفتوحین کو مہذب اور متمدن بنانا بڑا کام نہیں؟ کیا
مفتوحین کی تعلیم و تربیت اور انہیں علوم و فنون میں دسترس دلا نا بڑا کام نہیں؟ بخدا دنیا کے ہر کونے سے اس حقیقت
کی شناسائی کے بعد یہی پکار اٹھے گی کہ ابن وراق اگر تم کوئی وجود رکھتے ہو تو سن لو کہ تمہارا جھوٹا ہونا ظاہر ہوچکا ہے!!!
ہم یہ ماننے پر مجبور ہیں کہ ابن وراق ان جگہوں پر سراسر دجل، فریب اور جھوٹ سے کام لے رہا ہے.بہت
کوشش کی ڈھونڈنے کی کہ کہیں تو کوئی بات دیانت داری سے کہی ہو.ابن وراق کو اتنی سی شرم اور حیا بھی نہیں ملی کہ
خوبی کا اعتراف نہ کرے تو اس سے اعراض ہی کرلے.یہ شخص تو کمال بے حیائی سے ہر خوبی کا نہ صرف انکار کرتا
ہے بلکہ اسے خامی کی شکل میں پیش کرتا چلا جا رہا ہے.یہ بھی نہیں سوچا کہ قاری یہ تو سوچتا ہی ہوگا کہ اس کتاب کے
مطابق تو مذ ہب اسلام کی تو ہر بات ہی الٹ اور غلط ہے اور کوئی بات درست ہے ہی نہیں.کتاب ہے تو وہ گھٹیا
عربی زبان میں تعلیم ہے تو وہ عقل سے عاری؛ بانی ہے تو وہ عام اخلاق سے بھی بے بہرہ ( نعوذ باللہ ) پھر کروڑہا
انسانوں کی عقلیں کیوں ماری گئیں کہ ایک ایسے مذہب کو اس درجہ محبت اور اخلاص سے چمٹے کہ جان و مال لگا دیے،
دنیا بھر کی دشمنی مول لے لی، اپنے چھوٹے ، پرائے دشمن ہوئے ، جانیں گنوادیں مگر اس دین کو نہ چھوڑا؟
جس شخص کو بھی اسلامی تاریخ سے ادنی سا بھی مس ہے وہ تو یہ کتاب پڑھ کر دوہی نتیجے نکال سکتا ہے کہ ہر دور کے
پاگل، جاہل، نجی، کند ذہن ، بد دیانت وغیرہ وغیرہ اس دین کو تسلیم کرتے ہوں گے اور اسلام دراصل جرائم پیشہ
افراد کا ایک گروہ ہی ہوگا.مگر یہ نتیجہ تاریخ اور حالات کے آئینہ میں سچا اور درست نظر نہیں آتا کیونکہ اسلام قبول
کرنے کے بعد صحابہ نے وہ شان دکھائی کہ ایک دُنیا دنگ رہ گئی.ایسا بے نظیر جسمانی اور روحانی انقلاب ایک سچا
مذہب پیدا کرسکتا ہے.پس ہو نہ ہوا بن وراق جھوٹ بول رہا ہے.
Page 377
حفاظت قرآن کریم پر متفرق اعتراضات
361
حضرت مسیح موعود علیہ السلام تحریر فرماتے ہیں:.دوسرا معجزہ قرآن شریف کا جو ہمارے لیے حکم مشہود و محسوس کا رکھتا ہے وہ عجیب وغریب
تبدیلیاں ہیں جو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم میں برکت پیروی قرآن شریف واثر
صحبت آنحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم ظہور میں آئیں.جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ
مشرف باسلام ہونے سے پہلے کیسے اور کس طریق اور عادت کے آدمی تھے اور پھر بعد شرف
صحبت آنحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم و اتباع قرآن شریف کس رنگ میں آئے اور کیسے عقائد
میں ، اخلاق میں، چلن میں، گفتار میں، رفتار میں، کردار میں اور اپنی جمیع عادات خبیث حالت
سے منتقل ہو کر نہایت طیب اور پاک حالت میں داخل کئے گئے تو ہمیں اس تاثیر عظیم کو دیکھ کر جس
نے ان کے زنگ خوردہ وجودوں کو ایک عجیب تازگی بخشی اور روشنی اور چمک بخش دی تھی اقرار کرنا
پڑتا ہے کہ یہ تصرف ایک خارق عادت تصرف تھا جو خاص خدا تعالیٰ کے ہاتھ نے دکھایا.( بحوالہ مرزا غلام احمد اپنی تحریرات کی رو سے صفحہ 519)
ایک طرف اخلاق فاضلہ کی اعلی ترین مثالیں قائم کیں اور خدا کی عبادت اور تقویٰ اور توحید کے قیام کا ایسا
نمونہ دکھایا کہ اس کی مثال نہیں ملتی.جدید علوم کی نہ صرف بنیاد ڈالی بلکہ ان کو اپنے دور کے مطابق ان کی معراج
تک پہنچا دیا.علم کے ہر میدان میں ایسے ایسے کارنامے دکھائے کہ اور کسی قوم کو یہ علوشان نصیب ہی نہیں ہوئی.گہرے عقلی مضامین اور فلسفیانہ نکات نکالے اور پرانے فلسفہ کی اصلاح کی عظیم ترین سائنس دان پیدا کیے.جدید علوم کے بانی مبانی بنا اور بے شمار علوم کی بنیاد ڈالنا.اب یہ سعادت کون لے سکتا ہے؟ کیا یہ سب عالی
شان لوگ اس کتاب کے پیروکار اور حافظ تھے جس کی پیروی سے انسانیت جاتی رہتی ہے اور جس کے حفظ کرنے
سے دماغی صلاحیتوں کو نقصان ہوتا ہے؟ اور پیروکار بھی ایسے کہ جو اپنی ہر بات کی بنیاد قرآن کریم پر رکھتے تھے.پس پہلا نتیجہ ہی درست نظر آتا ہے کہ ابن وراق ہی جھوٹ بول رہا ہے.کچھ تو عقل سے کام لیتا کہ اسلام کی
خوبیوں میں سے کچھ خوبیاں تو تسلیم کرلوں کہ تا کہ لوگ کم از کم یہ ہی سمجھ لیں کہ کوتاہ بین جاہلوں میں ایک اور کا
اضافہ ہوا ہے نہ کہ یہ مجھنے لگیں کہ سلمان رشدی کا ساتھی پیدا ہو گیا ہے.اعتراضات پر اعتراضات جمع کرتا
جارہا ہے جس میں ہر قسم کا جھوٹ اور فریب کوٹ کوٹ کر بھرتا چلا جا رہا ہے.ہر جگہ دجل اور فریب گویا اس
کے علاوہ اس شخص کے پاس اس کے سوا کچھ ہے ہی نہیں.چنانچہ نام نہاد مسلمانوں کی طرف سے جماعت احمدیہ پر
ڈھائے جانے والے انسانیت سوز مظالم کا ذکر کرتا ہے.جو صرف یہ ذکر پڑھے وہ کہتا ہے کہ یہ بات درست ہے
لیکن اس کا دجل تب ظاہر ہوتا ہے جب ان مظالم کو پیش اصل اسلامی تعلیم کے طور پر کر دیتا ہے.پس ہم بآواز بلند
Page 378
الذكر المحفوظ
362
کہتے ہیں کہ ہمیں اسلام دشمنی پر بنی اور دجل و فریب سے گندھی ہوئی کسی ہمدردی کی ضرورت نہیں ! اسلام کی حسین
تعلیم میں کسی ظلم کی ادنی اسی بھی گنجائش نہیں ہے اور قرآن
کریم میں تو یہ بہت واضح اعلان ہے کہ:
إِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ
یعنی اللہ تعالیٰ تعالیٰ اپنے بندوں پرادنی سا بھی ظلم روا نہیں رکھتا
پس جماعت احمدیہ قرآن کریم کے اس اعلان پر بھی ایمان لاتی ہے اور غلطی خوردہ ظالموں کے ظلم پر خدا کی
عدالت میں اپنا مقدمہ پیش کرتی ہے اور جماعت کے نزدیک ابن وراق کی اس جھوٹی ہمدردی کی کوڑی کی بھی
حیثیت نہیں ہے.اتنے اعتراضات تو جمع کرنے سے ہی انسان کو تمام اعتراضات کا جواب مل جاتا ہے کیونکہ ایک کتاب میں
ایک بات اعتراض کے رنگ میں لکھی ہوتی ہے اور دوسری کتاب میں اسی اعتراض کا جواب مل جاتا ہے اور کسی
دوسرے پہلو پر اعتراض ہوتا ہے.بہر حال ان کا حال تو وہی ہے کہ:
يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّـهِ بِأَفْوَاهِهِم وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ
الْكَفِرُونَ (التوبة: 32)
یعنی وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں اور اللہ اپنے نور کو
بالضرور پورا کرنے والا ہے خواہ کافر کتنا ہی نا پسند کریں.ایک لطف کی بات یہ ہے کہ ابن اوراق کسی قسم کی شرم یا حیا کو اپنا منہ چھپانے کی وجہ قرار نہیں دیتا بلکہ کہتا ہے کہ
جس طرح سلمان رشدی کی کتاب کے بعد مسلمانوں نے جوش دکھایا تھا اور اسے جان کے لالے پڑ گئے تھے اسی
طرح مجھے بھی اپنی جان کی فکر ہے.ہم اس وقت مسلمانوں کے رویہ پر تبصرہ کر کے مضمون کو طویل نہیں کرنا چاہتے
لیکن یہ بیان کر دیتے ہیں یہ کہہ کر ابن وراق خود ہی اپنی کرتوتوں کو سلمان رشدی سے ملا رہا ہے اور اس حقیقت
سے کون اہل علم واقف نہیں کہ سلمان رشدی کی بدنام زمانہ کتاب کی بیہودگی پر صرف اہل اسلام ہی نہیں بلکہ غیر
مسلم مہذب دنیا نے بھی احتجاج کیا تھا.پس خود ہی ایک مکر وہ انسان سے جاملا.حضرت مرزا طاہر احمد صاحب خلیفہ المسیح الرابع رحمہ اللہ فرماتے ہیں:
ایسے مکروہ دماغ ہیں کہ کراہت آتی ہے ان میں جھانکتے ہوئے بھی.لیکن وہ خودا گلتے
ہیں تو دیکھنا پڑتا ہے.یہ بعض کی الٹیاں ہیں، قے ہے جو یہ باہر نکالتے رہتے ہیں وقتا فوقتا ،
اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اسلام کے خلاف کیسے بغض میں پلے ہوئے ہیں ؟...ایک جھوٹا
بے بنیاد الزام ہے تم ایک ایسی بات کو جو اس سے کئی گنا زیادہ ناممکن ہے اس کو قبول کر کے
Page 379
حفاظت قرآن کریم پر متفرق اعتراضات
363
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم پر حملہ آور ہوتے ہو جن کی نیتیوں کی پا کی تمہارے لوگوں کی
نیتوں سے ہزار گنا زیادہ قابل قبول اور قابل اعتماد ہے.یہ نا انصافی کی باتیں ہیں، بے حیائی
کی باتیں ہیں.تقویٰ سے خالی ، سچائی سے خالی.صرف وہی بات ہے کہ کھول رہے ہو غصے
میں، اسلام کیوں نہیں مٹا دیا گیا ایک ہی وقت تھا تمہاری نظر میں جب کہ اسلام کو کلیۂ نابود کیا
جاسکتا تھا اور نہیں ہو سکا نتیجہ کچھ اور نکل آیا.“
درس القرآن 5 رمضان 16 فروری 1994 ء زیر آیت و لقد صدقكم الله وعده اذ
تحسونهم......آل عمران 153 تا 155 )
جہاں تک ابن دراق اور اس قماش کے دوسرے لوگوں کی اس قسم کی گھٹیا کوششوں
کا تعلق ہے تو یہ سمجھنا چاہیے
کہ ہر دیانت دار اور سعید فطرت شخص جو ایسے اعتراض پڑھ کر تحقیق کی نظر سے اسلام کو دیکھے گا تو یہ اور اس جیسی
دوسری تمام کتب اور ان کتب کے لکھنے والوں سے متنفر ہو کر اسلام کے قریب ہی ہوگا نہ کہ دُور.حضرت مسیح موعود علیہ
السلام فرماتے ہیں:
یقیناً سمجھنا چاہیے کہ دین اسلام کو سچے دل سے وہی لوگ قبول کریں گے جو باعث سخت
اور پُر زور جگانے والی تحریکوں کے کتب دینیہ کی ورق گردانی میں لگ گئے ہیں اور جوش کے
ساتھ اس راہ کی طرف قدم اُٹھا رہے ہیں گو وہ قدم مخالفانہ ہی سہی.ہندوؤں کا وہ پہلا طریق
ہمیں بہت مایوس کرنے والا تھا جو اپنے دلوں میں وہ لوگ اس طرز کو زیادہ پسند کے لائق سمجھتے
تھے کہ مسلمانوں سے کوئی مذہبی بات چیت نہیں کرنی چاہیے اور ہاں میں ہاں ملا کر گزارہ کر لینا
چاہیے لیکن اب وہ مقابلہ پر آکر اور میدان میں کھڑے ہو کر ہمارے تیز ہتھیاروں کے نیچے
آپڑے ہیں اور اس صید قریب کی طرح ہو گئے جس کا ایک ہی ضرب سے کام تمام ہوسکتا ہے ان
کی آہوا نہ سرکشی سے ڈرنا نہیں چاہیے دشمن نہیں ہیں وہ تو ہمارے شکار ہیں...سوتم اُن کے
جوشوں سے گھبرا کر نومیدمت ہو کیونکہ وہ اندر ہی اندر اسلام کی ڈیوڑھی کے قریب آپہنچے ہیں.میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ جو لوگ مخالفانہ جوش سے بھرے ہوئے آج تمہیں نظر آتے ہیں
تھوڑے ہی زمانے کے بعد تم انہیں نہیں دیکھو گے.حال میں جو آریوں نے ہم لوگوں کی تحریک
سے مناظرات کی طرف قدم اُٹھایا ہے تو اس قدم اُٹھانے میں گو کیسی ہی سختی کے ساتھ اُن کا برتاؤ
ہے اور گو گالیوں اور گندی باتوں سے بھری ہوئی کتابیں وہ شائع کر رہے ہیں مگر وہ اپنے جوش
سے در حقیقت اسلام کیلئے اپنی قوم کی طرف راہ کھول رہے ہیں اور ہماری تحریکات کا واقعی طور پر
کوئی بد نتیجہ نہیں ہاں یہ تحریکات کو تہ نظروں کی نگاہ میں بدنما ہیں مگر کسی دن دیکھنا کہ یہ تحریکات
Page 380
الذكر المحفوظ
364
کیونکر بڑے بڑے سنگین دلوں کو اس طرف کھینچ لاتی ہیں.یہ رائے کوئی ظنی اور شکی رائے نہیں
بلکہ ایک یقینی اور قطعی امر ہے.لیکن افسوس اُن لوگوں پر جو خیر اور شر میں فرق نہیں کر سکتے اور
شتاب کاری کی راہ سے اعتراض کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں.خدا تعالیٰ نے ہمیں
مداہنہ سے تو صاف منع فرمایا ہے لیکن حق کے اظہار سے باندیشہ اس کی مرارت اور تلخی کے باز
آجانے کا کہیں حکم نہیں فرمایا.فتدبروا ايها العلماء المستعجلون الا تقرؤن الفرقان
مالكم كيف تحكمون.دراصل تہذیب حقیقی کی راہ وہی راہ ہے جس پر انبیاء علیہم السلام نے قدم مارا ہے جس میں
سخت الفاظ کا داروئے تلخ کی طرح گاہ گاہ استعمال کرنا حرام کی طرح نہیں سمجھا گیا بلکہ ایسے
درشت الفاظ کا اپنے محل پر بقدر ضرورت و مصلحت استعمال میں لانا ہر ایک مبلغ اور واعظ کا فرض
وقت ہے جس کے ادا کرنے میں کسی واعظ کا سستی اور کاہلی اختیار کرنا اس بات کی نشانی ہے کہ
غیر اللہ کا خوف جو شرک میں داخل ہے اس کے دل پر غالب اور ایمانی حالت اس کی ایسی کمزور
اور ضعیف ہے جیسے ایک کیڑے کی جان کمزور اور ضعیف ہوتی ہے.(ازالہ اوہام حصہ دوم روحانی خزائن جلد سوم صفحہ 116, 115 ایڈیشن اول صفحہ 25 تا 28 زیر
عنوان ہم اور ہمارے نکتہ چین)
Page 381
قرآن کریم کی معنوی محافظت
365
باب سوم
قرآن کریم کی معنوی محافظت
ان کو کہہ دے کہ تمہارے خیالات کیا چیز ہیں.ہدایت وہی ہے جو خدائے تعالیٰ
براہ راست آپ دیتا ہے ورنہ انسان اپنے غلط اجتہادات سے کتاب اللہ کے معنے بگاڑ
دیتا ہے اور کچھ کا کچھ کجھ لیتا ہے.وہ خدا ہی ہے جو غلطی نہیں کھاتا.لہذا ہدایت اس کی
ہدایت ہے.انسانوں کے اپنے خیالی معنے بھروسے کے لائق نہیں ہیں.( حضرت مرزا غلام احمد قادیانی امام الزماں علیہ السلام )
Page 383
قرآن کریم کی معنوی محافظت
367
قرآن کریم کی حفاظت کے حوالہ سے ایک بہت اہم پہلو کلام اللہ کے درست اور صحیح معانی ومطالب کی تعلیم ہے.سب سے بڑے معلم قرآن خود آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے.آپ کی ساری زندگی قرآن کریم کی تعلیم واشاعت
میں صرف ہوئی.آپ کے بارہ میں آپ کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنھا کی گواہی ہے کہ آپ
سرا پا قرآن تھے.قرآن کریم کی درس و تدریس اور اس کی تعلیم کی اشاعت کے لیے آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی
مساعی کا تعلیم القرآن کے عنوان کے تحت ایک مختصر خاکہ پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے.قرآن
کریم کی درست تفسیر کے لیے آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور آپ کی عطا کردہ تعلیم القرآن
بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے.چنانچہ آپ کے عطا کردہ تعلیم وفہم قرآن کے صحیح فہم اور ادراک کے لیے امت مرحومہ
میں بہت کام ہوا.امت مسلمہ میں بہت سے علوم کی بنیاد بلواسطہ یا بلا واسطہ قرآن کریم کے درست تفسیر اور اس کا
فہم ہی تھی.چنانچہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں علمانے تفسیر قرآن کے لیے اصول وضع کیسے
اور علوم تغییر کو ان کی معراج تک پہنچایا.حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:
ایک ذریعہ قرآن مجید کی حفاظت کا یہ تھا کہ اسلامی علوم کی بنیاد قرآن مجید پر قائم ہوئی.اس
ذریعہ سے اس کی ہر حرکت و سکون محفوظ ہو گئے.مثلاً نحو پیدا ہوئی تو قرآن مجید کی خدمت کے
لئے....پھر مسلمانوں نے تاریخ ایجاد کی تو قرآن مجید کی خدمت کی غرض سے کیونکہ قرآن مجید
میں مختلف اقوام کے حالات آئے تھے.ان کو جمع کرنے لگے تو باقی دنیا کے حالات ساتھ ہی جمع
کر دئیے.پھر علم حدیث شروع ہوا تو قرآن مجید کی خدمت کے لئے تا معلوم ہو سکے کہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے کیا معنے کئے ہیں.پھر اہل فلسفہ کے قرآن مجید پر اعتراضات کے دفعیہ کے لئے مسلمانوں نے فلسفہ وغیرہ علوم کی
تجدید کی اور علم منطق کے لئے نئی مگر زیادہ محقق راہ نکالی.پھر طب کی بنیاد بھی قرآن مجید کے توجہ
دلانے پر ہی قائم ہوئی.نحو میں مثالیں دیتے تھے تو قرآن مجید کی آیات کی.ادب میں بہترین مجموعہ
قرآن مجید کی آیات کو قراردیا گیا تھا.غرض ہر علم میں آیات قرآنی کو بطور حوالہ نقل کیا جاتا تھا اور میں
سمجھتا ہوں کہ اگر ان سب کتابوں سے آیات کو جمع کیا جائے تو ان سے بھی سارا قرآن جمع ہو جائے
گا.مسلمانوں میں قرآن کریم کی خدمت کے لئے دوسرے علوم کی طرف رجوع کا ایک ضمنی فائدہ یہ
بھی ہوا کہ پہلی کتابوں سے تو دنیوی علماء کا طبقہ سخت بے زار تھا مگر مسلمانوں میں سے ان علوم کے ماہر
ہمیشہ قرآن مجید کے خادم رہے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم سے علوم کا دشمن نہیں بلکہ مؤید ہے.( تفسیر کبیر جلد چہارم صفحه 52 مرتفسیر المجر آیت 10)
پس مسلمانوں نے قرآن کریم کے معانی سمجھنے کے لیے تمام علوم کو بطور خادم استعمال کیا اور قرآن کریم کے
Page 384
الذكر المحفوظ
368
نور سے اپنی کتب منور کیں.صرف علوم تفسیر کے حوالہ سے ہی دیکھا جائے تو امت مسلمہ میں بے شمار کام ہوا اور
قرآنی معارف سے ہزاروں ہزار صفحات جگمگانے لگے.ان علوم کی اہمیت اور ان سے استفادہ کی تاکید کرتے
ہوئے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی معہود علیہ السلام فرماتے ہیں:
قرآن شریف سے اعراض کی دو صورتیں ہوتی ہیں ایک صوری اور ایک معنوی.صوری یہ کہ کبھی کلام الہی کو پڑھا ہی نہ جاوے جیسے اکثر لوگ مسلمان کہلاتے ہیں مگر وہ قرآن
شریف کی عبارت تک سے بالکل غافل ہیں اور ایک معنوی کہ تلاوت تو کرتا ہے مگر اس کی
برکات و انوار و رحمت الہی پر ایمان نہیں ہوتا.پس دونو اعراضوں میں سے کوئی اعراض ہو
( ملفوظات جلد سوم صفحہ 519 )
اس سے پر ہیز کرنا چاہیئے.ایک دوسری جگہ تفسیر کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا:
ہم ہر گز فتوی نہیں دیتے کہ قرآن کا صرف ترجمہ پڑھا جاوے.اس سے قرآن کا اعجاز
باطل ہوتا ہے.جو شخص یہ کہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ قرآن دنیا میں نہ رہے ( ملفوظات جلد سوم جلد 265)
صرف قرآن کا ترجمہ اصل میں مفید نہیں جب تک اس کے ساتھ تفسیر نہ ہو مثلاً غیر
الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِین کی نسبت کسی کو کیا سمجھ آ سکتا ہے کہ اس سے مراد یہودونصاریٰ
ہیں جب تک کہ کھول کر نہ بتلایا جاوے اور پھر یہ دعا مسلمانوں کو کیوں سکھلائی گئی.اس کا یہی منشا
تھا کہ جیسے یہودیوں نے حضرت مسیح کا انکار کر کے خدا کا غضب کمایا.ایسے ہی آخری زمانہ میں
اس امت نے بھی مسیح موعود کا انکار کر کے خدا کا غضب کمانا تھا اسی لیے اول ہی ان کو بطور پیشگوئی
کے اطلاع دی گئی کہ سعید روحیں اس وقت غضب سے بچ سکیں.(ملفوظات جلد سوم صفحہ 449)
یہ بات بہت عام فہم ہے کہ آئندہ زمانوں میں لفظی محافظت کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی معنوی محافظت
اور ہمہ وقت نگرانی بھی آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بس سے باہر تھی.آپ کی وفات کے بعد اگر ہر شخص اپنے طور
پر قرآن کریم کے معانی کرنے لگتا تو بہت اختلاف پیدا ہوتا.ظاہر
سی بات ہے کہ اگر قرآن کریم کے الفاظ تو محفوظ
ہوں لیکن اس کے معانی اور مطالب میں بہت زیادہ اختلاف پیدا ہو جائے تو اس کی لفظی حفاظت بنی نوع کے کس
فائدہ کی ؟ گو مسلمانوں نے قرآن کریم کی ایضاح و تفسیر کے لیے ایسے ایسے اصول تفسیر وضع کیے جن پر کار بند رہ کر
بہت حد تک درست معانی اور مطالب اخذ کیے جاسکتے ہیں لیکن پھر بھی شک کا ایک دروازہ کھلا رہ جاتا ہے کیونکہ
ان معانی اور مطالب کی بنیاد بہر حال انسانی عقل پر ہوتی ہے اور بالفاظ حضرت مسیح موعود علیہ السلام
ے عقل اندھی ہے اگر نیر الہام نہ ہو
پس خدا تعالیٰ نے محافظت قرآن کریم کے ظاہری سامانوں کے ساتھ ساتھ ایک ایسا انتظام بھی فرمایا جو غیر
Page 385
قرآن کریم کی معنوی محافظت
369
اللہ کے دخل سے بکلی پاک ہے اور وہ الہام ہے.چنانچہ رسول کریم ﷺ امت کو بشارت دیتے ہوئے فرماتے ہیں:
إِنَّ اللهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِئَةٍ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِيْنَهَا
(سنن ابی داؤد کتاب الملاحم باب ما جاء في قرن المائة)
اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سر پر ایسے لوگ مبعوث کرتا رہے گا جو اس صدی کی ضروریات کے
مطابق تجدید دین کریں گے.حضرت مرزا غلام احمد قادیانی صاحب مسیح موعود و مہدی معہود علیہ السلام فرماتے ہیں:
صرف رسمی اور ظاہری طور پر قرآن شریف کے تراجم پھیلانا یا فقط کتب دینیہ اور احادیث نبویہ کو
اردو یا فارسی میں ترجمہ کر کے رواج دینا یا بدعات سے بھرے ہوئے خشک طریقے جیسے زمانہ حال کے
اکثر مشائخ کا دستور ہورہا ہے سکھلانا یہ امور ایسے نہیں ہیں جن کو کامل اور واقعی طور پر تجدید دین کہا
جائے بلکہ مؤخر الذکر تو شیطانی راہوں کی تجدید ہے اور دین کا ر ہنزن.قرآن شریف اور احادیث صحیحہ
کو دنیا میں پھیلانا بے شک عمدہ طریق ہے مگر رسمی طور پر اور تکلف اور فکر اور خوض سے یہ کام کرنا اور اپنا
نفس واقعی طور پر حدیث اور قرآن کا مورد نہ ہونا ایسی ظاہری اور بے مغز خدمتیں ہر ایک با علم آدمی کر
سکتا ہے اور ہمیشہ جاری ہیں ان کو مجددیت سے کچھ علاقہ نہیں.یہ تمام امور خدا تعالیٰ کے نزدیک فقط
استخوان فروشی ہے اس سے بڑھ کر نہیں.اللہ جلشانہ فرماتا ہے لِمَ تَقُولُونَ مَالَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ
مَقْتًا عِنْدَ الله أَن تَقُولُوا مَالَا تَفْعَلُونَ (الصف: 443) اور فرماتا ہے يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّ كُمْ مَّنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ (المائدة:106).اندھا اندھے کو کیا
راہ دکھا ویگا اور مجزوم دوسروں کے بدنوں کو کیا صاف کریگا.تجدید دین وہ پاک کیفیت ہے کہ اول
عاشقانہ جوش کے ساتھ اس پاک دل پر نازل ہوتی ہے کہ جو مکالمہ الہی کے درجہ تک پہنچ گیا ہو پھر
دوسروں میں جلد یا دیر سے اسکی سرایت ہوتی ہے.جولوگ خدا تعالے کی طرف سے مجددیت کی قوت
پاتے ہیں وہ نرے استخوان فروش نہیں ہوتے بلکہ وہ واقعی طور پر نائب رسول اللہ ﷺ اور روحانی طور
پر آنجناب کے خلیفہ ہوتے ہیں.خدا تعالیٰ انہیں ان تمام نعمتوں کا وارث بناتا ہے جو نبیوں اور رسولوں
کو دی جاتی ہیں اور ان کی باتیں از قبیل جوشیدن ہوتی ہیں نہ محض از قبیل پوشیدن اور وہ حال سے
بولتے ہیں نہ مجر و قال سے اور خدا تعالیٰ کے الہام کی تجلی اُنکے دلوں پر ہوتی ہے اور وہ ہر ایک مشکل
کے وقت روح القدس سے سکھلائے جاتے ہیں اور انکی گفتار اور کردار میں دنیا پرستی کی ملونی نہیں ہوتی
کیونکہ وہ بکلی مصفا کئے گئے اور بتمام و کمال کھینچے گئے ہیں.(فتح اسلام روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 6-7 حاشیہ )
Page 386
الذكر المحفوظ
370
لمصل
حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب خلیفہ اسیح الثانی اصلح الموعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:
یہ ظاہر ہے کہ اگر خدا تعالیٰ کی طرف سے الہام پا کر کوئی شخص اس کے صحیح معانی نہ بتائے.تو کون یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ وہ اس کا صحیح مطلب بیان کر رہا ہے یا اس کے مطابق عمل
کر رہا ہے.یہ نقص اسی صورت میں دور ہو سکتا ہے کہ تھوڑے تھوڑے عرصہ کے بعد ایسے لوگ
کھڑے ہوتے رہیں جو کتاب کے صحیح مفہوم کی طرف لوگوں کو لاتے رہیں اور یہ حفاظت دائمی طور
پر قرآن کریم ہی کو حاصل ہے.بے شک دوسری کتب سماویہ کو بھی اس عرصہ میں کہ وہ زندہ کتب
تھیں یعنی دنیا کے لیے قابل عمل تھیں، یہ حفاظت حاصل تھی مگر اب نہیں.اب صرف قرآن کریم ہی
کو یہ حفاظت حاصل ہے.صرف اس کے ماننے والے ہر زمانہ میں خدا تعالیٰ سے براہ راست الہام
پانے کے مدعی ہوتے چلے آئے ہیں.اور اس زمانہ میں کہ دین سے غفلت انتہا کو پہنچ گئی ہے.اللہ
تعالیٰ نے ایک ایسا مامور مبعوث فرمایا ہے.جس نے کلی طور پر قرآن کی تفسیروں کوزوائد اور حشو سے
پاک کر کے اصلی صورت میں دنیا کے سامنے پیش کیا ہے.حتی کہ قرآن جو اسی زمانہ کے علوم کے
سامنے ایک معذرت خواہ کی صورت میں کھڑا تھا.اب ایک حملہ آور کی صورت میں کھڑا ہے.جس
کے سامنے سب فلسفے اور مذاہب اس طرح بھاگ رہے ہیں جیسے شیر کے سامنے سے
(تفسیر کبیر جلد چہارم صفحه 52 زیرتفسیر المجر آیت 10)
اللہ تعالیٰ کے وعدہ کے مطابق اس زمانہ میں مبعوث ہونے والے مامور حضرت مرزا غلام احمد قادیانی صاحب
مسیح موعود و مہدی معہود علیہ السلام ہیں.آپ فرماتے ہیں:
اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدہ کے موافق کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ
لَحفِظُونَ(الحجر: 10) قرآن شریف کی عظمت کو قائم کرنے کے لیے چودھویں صدی کے سر
لومڑ.فسبحان الله الملك العزيز
( ملفوظات جلد اوّل صفحہ 433)
پر مجھے بھیجا.وہ پاک وعدہ جس کو یہ پیارے الفاظ ادا کر رہے ہیں کہ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ
لَحفِظُون وہ انہیں دنوں کے لیے وعدہ ہے جو بتلا رہا کہ جب اسلام پر سخت بلا کا زمانہ آئے گا
اور سخت دشمن اس کے مقابل کھڑا ہو گا اور سخت طوفان پیدا ہو گا تب خدائے تعالیٰ آپ اس کا
معالجہ کرے گا اور آپ اس طوفان سے بچنے کے لیے کوئی کشتی عنایت کرے گا.وہ کشتی اس عاجز
کی دعوت ہے.آئینہ کمالات اسلام روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 264 حاشیہ)
اس وقت میرے مامور ہونے پر بہت سی شہادتیں ہیں.اول اندرونی شہادت، دوم بیرونی
شہادت ہوم صدی کے سر پر آنے والے مجدد کی نسبت حدیث میج، چهارم إنا نحن نزلنا
Page 387
قرآن کریم کی معنوی محافظت
371
الذِّكْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحفِظُون (الحجر: 10) کا وعدہ حفاظت.( ملفوظات جلد دوم صفحہ 360 )
آپ فرماتے ہیں:
ما مسلمانیم
از فضل خدا
مصطفه ما را امام و
مقتدا
ہم خدا کے فضل
سے پیشوا ہیں
مسلمان ہیں.محمد مصطفے ہمارے امام اور
آں کتاب حق که قرآن نام اوست باده عرفان ما از جام اوست
خدا کی وہ کتاب جس کا نام قرآن ہے ہماری شراب معرفت اُسی جام سے ہے
آل رسولے کش محمد هست نام دامن پاکش بدست ما مدام!
وہ رسول جس کا نام محمد ہے.اُس کا مقدس دامن ہر وقت ہمارے ہاتھ میں ہے
مہر او با شیر شد اندر
بدن جان شد و با جان بدر خواهد شدن
اُس کی محبت ماں کے دودھ کے ساتھ ہمارے بدن میں داخل ہوئی وہ جان بن گئی اور جان کے ساتھ ہی باہر نکلے گی
هست او خیر الرسل خیر الانام ہر نبوت را برو شد اختتام
وہی خیر الرسل اور خیرالانام ہے اور ہر قسم کی نبوت کی تکمیل اُس پر ہوگئی
ما از و یا بیم ہر نور و کمال! وصل دلدار ازل ہے او محال
ہم ہر روشنی اور ہر کمال اُسی سے حاصل کرتے ہیں محبوب ازلی کا وصل بغیر اُس کے ناممکن ہے
حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی معہود علیہ السلام قرآن کریم کی معنوی حفاظت اور اس کی
ضرورت اور معنوی حفاظت کے الہی انتظام کے بارہ میں فرماتے ہیں:
علاوہ اس کے مشاہدہ صاف بتلا رہا ہے کہ جو لوگ صادقوں کی صحبت سے لا پروا ہوکر عمر
گذارتے ہیں ان کے علوم و فنون جسمانی جذبات سے ان کو ہرگز صاف نہیں کر سکتے اور کم سے کم
اتنا ہی مرتبہ اسلام کا کہ دلی یقین اس بات پر ہو کہ خدا ہے ان کو ہرگز حاصل نہیں ہو سکتا اور جس
طرح وہ اپنی اس دولت پر یقین رکھتے ہیں جو ان کے صندوقوں میں بند ہو یا اپنے ان مکانات پر
جوان کے قبضہ میں ہوں ہرگز ان کو ایسا یقین خدا تعالیٰ پر
نہیں ہوتا.وہ سم الفار کھانے سے ڈرتے
ہیں کیونکہ وہ یقیناً جانتے ہیں کہ وہ ایک زہر مہلک ہے لیکن گناہوں کی زہر سے نہیں ڈرتے
حالانکہ ہر روز قرآن میں پڑھتے ہیں إِنَّهُ مَنْ يَّأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمُ لَا يَمُوتُ فِيهَا
وَلَا يَحُى (طه: ۷۵) پس سچ تو یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالی کونہیں پہچانتا وہ قرآن کو بھی نہیں پہنچان
سکتا.ہاں یہ بات بھی درست ہے کہ قرآن ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے مگر قرآن کی ہدایتیں اس
Page 388
الذكر المحفوظ
372
شخص کے وجود کے ساتھ وابستہ ہیں.جس پر قرآن نازل ہوا یا وہ شخص جو منجانب اللہ اس کا قائم
مقام ٹھہرایا گیا.اگر قرآن اکیلا ہی کافی ہوتا تو خدا تعالیٰ قادر تھا کہ قدرتی طور پر درختوں کے پتوں
پر قرآن
لکھا جاتا یا لکھا لکھایا آسمان سے نازل ہو جاتا مگر خدا تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا بلکہ قرآن کو دنیا
میں نہیں بھیجا جب تک معلم القرآن
دنیا میں نہیں بھیجا گیا.قرآن کریم کو کھول کر دیکھو کتنے مقام
میں اس مضمون کی آیتیں ہیں کہ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ( الجمعة: ۳) یعنی وہ نبی کریم
صلی اللہ علیہ والہ وسلم قرآن اور قرآنی حکمت لوگوں سکھلاتا ہے اور پھر ایک جگہ اور فرماتا ہے وَ لَا
يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُون (الواقعة: ۸۰) یعنی قرآن کے حقائق و دقائق انہیں پر کھلتے ہیں جو پاک
کئے گئے ہیں.پس ان آیات سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کے سمجھنے کے لیے ایک ایسے
معلم کی ضرورت ہے جس کو خدا تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پاک کیا ہو.اگر قرآن کے سیکھنے کے
لیے معلم کی حاجت نہ ہوتی تو ابتدائے زمانہ میں بھی نہ ہوتی اور یہ کہنا کہ ابتداء میں تو حل مشکلات
قرآن کے لیے ایک معلم کی ضرورت تھی لیکن جب حل ہو گئیں تو اب کیا ضرورت ہے؟ اس کا
جواب یہ ہے کہ حل شدہ بھی ایک مدت کے بعد پھر قابل حل ہو جاتی ہیں ماسوا اس کے امت کو
ہر یک زمانہ میں نئی مشکلات بھی تو پیش آتی ہیں اور قرآن جامع جمیع علوم تو ہے لیکن یہ ضروری
نہیں کہ ایک ہی زمانہ میں اس کے تمام علوم ظاہر ہو جائیں بلکہ جیسی جیسی مشکلات کا سامنا ہوتا
ہے ویسے ویسے قرآنی علوم کھلتے ہیں اور ہر یک زمانہ کی مشکلات کے مناسب حال ان مشکلات کو
حل کرنے والے روحانی معلم بھیجے جاتے ہیں جو وارث رسل ہوتے ہیں اور ظلتی طور پر رسولوں
کے کمالات کو پاتے ہیں اور جس مجدد کی کاروائیاں کسی ایک رسول کی منصبی کاروائیوں سے شدید
مشابہت رکھتی ہیں وہ عنداللہ اُسی رسول کے نام سے پکارا جاتا ہے.اب نئے معلموں کی اس وجہ سے بھی ضرورت پڑتی ہے کہ بعض حصے تعلیم قرآن شریف کے از
قبیل حال ہیں نہ از قبیل قال اور آنحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے جو پہلے معلّم اور اصل وارث
اس تخت کے ہیں حالی طور پر ان دقائق کو اپنے صحابہ کو سمجھایا ہے.مثلاً خدا تعالیٰ کا یہ کہنا کہ میں
عالم الغیب ہوں اور میں مجیب الدعوات ہوں اور میں قادر ہوں اور میں دعاؤں کو قبول کرتا ہوں
اور طالبوں کو حقیقی روشنی تک پہنچاتا ہوں اور میں اپنے صادق بندوں کو الہام دیتا ہوں اور جس پر
چاہتا ہوں اپنے بندوں میں سے اپنی روح ڈالتا ہوں یہ تمام باتیں ایسی ہیں کہ جب تک معلم خود
ان کا نمونہ بن کر نہ دکھلاوے تب تک یہ کسی طرح سمجھ نہیں آسکتیں پس ظاہر ہے کہ صرف ظاہری
علماء خود اندھے ہیں ان تعلیمات کو سمجھا نہیں سکتے بلکہ وہ تو اپنے شاگردوں کو ہر وقت اسلام کی
Page 389
373
قرآن کریم کی معنوی محافظت
عظمت سے بدظن کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ باتیں آگے نہیں بلکہ پیچھے رہ گئی ہیں اور ان کے
ایسے بیانات سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ گویا اسلام اب زندہ مذہب نہیں اور اس کی حقیقی تعلیم پانے
کے لیے اب کوئی بھی راہ نہیں.لیکن ظاہر ہے کہ اگر خدا تعالیٰ کا اپنی مخلوق کے لیے یہ ارادہ ہے کہ
وہ ہمیشہ قرآن کریم کے چشمہ سے ان کو پانی پلا دے تو بیشک وہ اپنے ان قوانین قدیمہ کی رعائیت
کرے گا جو قدیم سے کرتا آیا ہے.اور اگر قرآن کی تعلیم صرف اسی حد تک محدود ہے جس حد تک
ایک تجربہ کار اور لطیف الفکر فلاسفر کی تعلیم محدود ہوسکتی ہے اور آسمانی تعلیم جو محض حال کے نمونہ
سے سمجھائی جاتی ہے اس میں نہیں تو پھر نعوذ باللہ قرآن کا آنالا حاصل ہے.مگر میں جانتا ہوں کہ
اگر کوئی ایک دم کے واسطے بھی اس مسئلہ میں فکر کرے کہ انبیاء کی تعلیم اور حکیموں کی تعلیم میں
بصورت فرض کرنے صحت ہر وہ تعلیم کے مابہ الامتیاز کیا ہے تو بجز اس کے اور کوئی مابہ الامتیاز قرار
نہیں دے سکتا کہ انبیاء کی تعلیم کا بہت سا حصہ فوق العقل ہے جو بجز حالی تفہیم اور تعلیم کے اور کسی
راہ سے سمجھ ہی نہیں آ سکتا اور اس حصہ کو وہی لوگ دلنشین کرا سکتے ہیں جو صاحب حال ہوں مثلاً
ایسے ایسے مسائل کہ اس طرح پر فرشتے جان نکالتے ہیں اور پھر یوں آسمان پر لے جاتے ہیں اور
پھر قبر میں حساب اس طور سے ہوتا ہے اور بہشت ایسا ہے اور دوزخ ایسا اور پل صراط ایسا اور عرش
اللہ کو چار فرشتے اٹھا رہے ہیں اور پھر قیامت کو آٹھ اٹھائیں گے اور اس طرح پر خدا اپنے بندوں
پر وحی نازل کرتا ہے یا مکاشفات کا دروازہ ان پر کھولتا ہے یہ تمام حالی تعلیم ہے اور مجرد قیل وقال
سے سمجھ نہیں آسکتی اور جب کہ یہ حال ہے تو پھر میں دوبارہ کہتا ہوں کہ اگر اللہ جلشانہ نے اپنے
بندوں کے لیے یہ ارادہ فرمایا ہے کہ اس کی کتاب کا یہ حصہ تعلیم ابتدائی زمانہ تک محدود نہ رہے تو
بیشک اس نے یہ بھی انتظام کیا ہوگا کہ اس حصہ تعلیم کے معلم بھی ہمیشہ آتے رہیں کیونکہ حصہ حالی
تعلیم کا بغیر توسط ان معلموں کے جو مرتبہ پر پہنچ گئے ہوں ہر گز سمجھ نہیں آسکتا اور دنیا ذرہ ذرہ بات
پر ٹھوکریں کھاتی ہے پس اگر اسلام میں بعد آنحضرت ﷺ ایسے معلم نہیں آئے جن میں خلتی
طور پر نور نبوت تھا تو گویا خدا تعالیٰ نے عملاً قرآن کو ضائع کیا کہ اس کے حقیقی اور واقعی طور پر سمجھنے
والے بہت جلد دنیا سے اٹھا لیے مگر یہ بات اس کے وعدہ کے برخلاف ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے انا
نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحفِظُون یعنی ہم نے ہی قرآن اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت
کرتے رہیں گے.اب میں نہیں سمجھ سکتا کہ اگر قرآن کے سمجھنے والے ہی باقی نہ رہے اور اس پر
یقینی اور مالی طور پر ایمان لانے والے زاویہ عدم میں مختفی ہو گئے تو پھر قرآن کی حفاظت کیا ہوئی.کیا حفاظت سے یہ حفاظت مراد ہے کہ قرآن بہت سے خوشخط نسخوں میں تحریر ہو کر قیامت تک
Page 390
الذكر المحفوظ
374
صندوقوں میں بندر ہے گا جیسے بعض مدفون خزا نے گوکسی کے کام نہیں آتے مگر زمین کے نیچے محفوظ
پڑے رہتے ہیں کیا کوئی سمجھ سکتا ہے کہ اس آیت سے خدا تعالی کا یہی منشاء ہے.اگر یہی منشاء ہے
تو ایسی حفاظت کوئی کمال کی بات نہیں بلکہ یہ تو ہنسی کی بات ہے اور ایسی حفاظت کا منہ پر لانا
دشمنوں سے ٹھٹھا کرانا ہے کیونکہ جبکہ علت غائی مفقود ہو تو ظاہری حفاظت سے کیا فائدہ ممکن ہے
کہ کسی گڑھے میں کوئی نسخہ انجیل یا توریت کا بھی ایسا ہی محفوظ پڑا ہوا اور دنیا میں تو ہزار ہا کتابیں
اسی قسم کی پائی جاتی ہیں کہ جو یقینی طور پر بغیر کسی کمی بیشی کے کسی مؤلف کی تالیف سمجھی گئی ہیں تو اس
میں کمال کیا ہوا اور امت کو خصوصیت کے ساتھ فائدہ کیا پہنچا؟ گو اس سے انکار نہیں کہ قرآن کی
حفاظت ظاہری بھی دنیا کی تمام کتابوں سے بڑھ کر ہے اور خارق عادت بھی لیکن خدا تعالیٰ جس
کی روحانی امور پر نظر ہے ہر گز اس کی ذات کی نسبت یہ گمان نہیں کر سکتے کہ اتنی حفاظت سے مراد
صرف الفاظ اور حروف کا محفوظ رکھنا ہی مراد لیا ہے حالانکہ ذکر کا لفظ بھی صریح گواہی دے رہا ہے
که قرآن بحیثیت ذکر ہونے کے قیامت تک محفوظ رہے گا اور اس کے حقیقی ذاکر ہمیشہ پیدا
ہوتے رہیں گے اور اس پر ایک اور آیت بھی بین قرینہ ہے اور وہ یہ ہے بَلْ هُوَ أَيَاتٌ بَيِّنَاتُ
فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ یعنی قرآن آیات بینات ہیں جو اہل علم کے سینوں میں ہیں.پس ظاہر ہے کہ اس آیت کے یہی معنی ہیں کہ مومنوں کو قرآن کریم کا علم اور نیز اس پر عمل عطا کیا
گیا ہے اور جب کہ قرآن کی جگہ مومنوں کے سینے ٹھہرے تو پھر یہ آیت کہ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا
الذِكْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحفِظُون بجز اس کے اور کیا معنی رکھتی ہے کہ قرآن سینوں سے
محو نہیں کیا جائے
گا جس طرح کہ توریت اور انجیل یہود اور نصاریٰ کے سینوں سے محو کی گئی اور گوتو ریت اور انجیل
ان کے ہاتھوں اور ان کے صندوقوں میں تھی لیکن ان کے دلوں سے محو ہو گئی یعنی ان کے دل اس پر
قائم نہ رہے اور انہوں نے توریت اور انجیل کو اپنے دلوں میں قائم اور بحال نہ کیا.غرض یہ آیت
بلند آواز سے پکار رہی ہے کہ کوئی حصہ قرآن کا بر باد اور ضائع نہیں ہوگا اور جس طرح روز اول
سے اس کا پودا دلوں میں جمایا گیا.یہی سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا.دوم جس طرح پر کہ عقل اس بات کو واجب اور تم ٹھہراتی ہے کہ کتب الہی کی دائمی تعلیم اور
تفہیم کے لیے ضروری ہے کہ ہمیشہ انبیاء کی طرح
وقتا فوقتا ملہم اور مکام اور صاحب علم لدنی پیدا
ہوتے رہیں.اسی طرح جب ہم قرآن پر نظر ڈالتے ہیں اور غور کی نگہ سے اس کو دیکھتے ہیں تو وہ
بھی بآواز بلند یہی فرما رہا ہے کہ روحانی معلموں کا ہمیشہ کے لیے ہونا اس کے ارادہ قدیم میں مقرر
ہو چکا ہے دیکھو اللہ جل شانہ فرماتا ہے وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمُكتُ فِي الْأَرْضِ الجُزو نمبر ١٣
Page 391
قرآن کریم کی معنوی محافظت
375
یعنی جو چیز انسانوں کو نفع پہنچاتی ہے وہ زمین پر باقی رہتی ہے اب ظاہر ہے کہ دنیا میں زیادہ تر
انسانوں
کو نفع پہنچانے والے گروہ انبیاء ہیں کہ جو خوارق سے معجزات سے، پیشگوئیوں سے، حقائق
سے ، معارف سے، اپنی راستبازی کے نمونہ سے انسانوں کے ایمان کو قومی کرتے ہیں اور حق کے
طالبوں کو دینی نفع پہنچاتے ہیں اور یہ بھی ظاہر ہے کہ وہ دنیا میں کچھ بہت مدت تک نہیں رہتے بلکہ
تھوڑی سی زندگی بسر کر کے اس عالم سے اٹھائے جاتے ہیں.لیکن آیت کے مضمون میں خلاف
نہیں اور ممکن نہیں کہ خدا تعالیٰ کا کلام خلاف واقع ہو.پس انبیاء کی طرف نسبت دیکر معنی آیت
کے یوں ہوں گے کہ انبیاء من حیث الظل باقی رکھے جاتے ہیں اور خدا تعالی ظلمی طور پر ہر یک
ضرورت کے وقت میں کسی اپنے بندہ کو ان کی نظیر اور مثیل پیدا کر دیتا ہے جو انہیں کے رنگ میں
ہوکر ان کی دائمی زندگی کا موجب ہوتا ہے اور اسی ظلی وجود قائم رکھنے کے لیے خدا تعالیٰ نے اپنے
بندوں کو یہ دعا سکھائی ہے اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ یعنی
اے خدا ہمارے ہمیں وہ سیدھی راہ دکھا جو تیرے ان بندوں کی راہ ہے جن پر تیرا انعام ہے اور
ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ کا انعام جو انبیاء پر ہوا تھا جس کے مانگنے کے لیے اس دعا میں حکم ہے اور وہ
درم اور دینار کی قسم میں سے نہیں بلکہ وہ انوار اور برکات اور محبت اور یقین اور خوارق اور تائید سماوی
اور قبولیت وار معرفت تامہ کاملہ وروحی اور کشف کا انعام ہے اور خدا تعالیٰ نے اس امت کو اس
انعام کے مانگنے کے لیے بھی حکم فرمایا کہ اول اس انعام کے عطا کرنے کا ارادہ بھی کر لیا.پس اس
آیت سے بھی کھلے کھلے طور پر یہی ثابت ہوا کہ خدا تعالی اس امت کو ظنی طور پر تمام انبیاء کا وارث
ٹھہراتا ہے تا انبیاء کا وجود ظلمی طور پر ہمیشہ باقی رہے اور دنیا ان کے وجود سے بھی خالی نہ ہو اور نہ
صرف دعا کے لیے حکم کیا بلکہ ایک آیت میں وعدہ بھی فرمایا ہے اور وہ یہ ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا
فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا یعنی جو لوگ ہماری راہ میں جو صراط مستقیم ہے مجاہدہ کریں گے تو ہم ان کو
اپنی راہیں بتلادیں گے اور ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ کی راہیں وہی ہیں جو انبیاء کو دکھلائی گئیں تھیں.پھر بعض اور آیات ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ ضرور خداوند کریم نے یہی ارادہ فرمایا ہے کہ
روحانی معلم جو انبیاء کے وارث ہیں ہمیشہ ہوتے رہیں اور وہ یہ ہیں.وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمُ
وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ.وَلَا يَزَالُ
الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيهُمُ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْتَحُلُّ قَرِيباً مِّنْ دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ
اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَاد الجزو نمبر ١٣ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا یعنی خدا تعالیٰ
نے
تمہارے لیے اے مومنان امت محمدیہ علیہ وعدہ کیا ہے کہ تمہیں بھی وہ زمین میں خلیفہ کرے گا
Page 392
الذكر المحفوظ
376
جیسا کہ تم سے پہلوں کو کیا اور ہمیشہ کفار پر کسی قسم کی کوفتیں جسمانی ہوں یا روحانی پڑتی رہیں گی یا ان
کے گھر سے نزدیک آجائیں گی.یہاں تک کہ خدا تعالیٰ کا وعدہ آپہنچے گا اور خدا تعالیٰ اپنے وعدوں
میں تخلف نہیں کرتا اور ہم کسی قوم پر عذاب نازل نہیں کرتے جب تک ایک رسول بھیج نہ لیں.ان آیات کو اگر کوئی شخص تامل اور غور کی نظر سے دیکھے تو میں کیونکر کہوں کہ وہ اس بات کو سمجھ نہ
جائے کہ خدا تعالیٰ اس امت کے لیے خلافت دائمی کا صاف وعدہ فرماتا ہے.اگر خلافت دائمی نہیں
تھی تو شریعت موسوی کے خلیفوں سے تشبیہہ دینا کیا معنی رکھتا تھا اور اگر خلافت راشدہ صرف تھیں
برس تک رہ کر پھر ہمیشہ کے لیے اس کا دور ختم ہو گیا تھا اس سے لازم آتا ہے کہ خدا تعالیٰ کا ہرگز یہ
ارادہ نہ تھا کہ اس امت پر ہمیشہ کے لیے ابواب سعادت مفتوح رکھے کیونکہ روحانی سلسلہ کی موت
سے دین کی موت لازم آتی ہے اور ایسامذہب ہرگز زندہ نہیں کہلا سکتا جس کے قبول کرنے والے
خود اپنی زبان سے ہی یہ اقرار کریں کہ تیرہ سو برس سے یہ مذہب مرا ہوا ہے اور خدا تعالیٰ نے اس
مذہب کے لیے ہر گز یہ ارادہ نہیں کیا کہ حقیقی زندگی کا وہ نور جو نبی کریم کے سینہ میں تھاوہ توارث کے
طور پر دوسروں میں چلا آوے.(شہادۃ القرآن روحانی خزائن جلد ششم صفحه 347 تا 351)
امام الزماں علیہ السلام ایک دوسری جگہ مسلمانوں کو خواب غفلت سے جاگنے اور قرآن کریم کا صحیح فہم حاصل
کرنے کی دعوت دیتے ہوئے فرماتے ہیں.اے بزرگان اسلام! خدا تعالیٰ آپ لوگوں کے دلوں میں تمام فرقوں سے بڑھ کر نیک ارادے
پیدا کرے اور اس نازک وقت میں آپ لوگوں کو اپنے پیارے دین کا سچا خادم بناوے.میں اس
وقت محض اللہ اس ضروری امر سے اطلاع دیتا ہوں کہ مجھے خدا تعالیٰ نے چودھوں صدی کے سر پر
اپنی طرف سے مامور کر کے دین متین اسلام کی تجدید اور تائید کے لئے بھیجا ہے تاکہ میں اس پر آشوب
زمانہ میں قرآن کی خوبیاں اور حضرت رسول اللہ ﷺ کی عظمتیں ظاہر کروں اور ان تمام دشمنوں کو
جو اسلام پر حملہ کر رہے ہیں ان نوروں اور برکات اور خوارق اور علوم لدنیہ کی مدد سے جواب دوں
جو مجھ کو عطا کئے گئے ہیں.بركات الدعاروحانی خزائن جلد 6 صفحہ 34 )
خدا تعالیٰ نے مجھے چودھویں صدی کے سر پر اس تجدید ایمان اور معرفت کے لئے مبعوث
فرمایا ہے اور اس
کی تائید اور فضل سے میرے ہاتھ پر آسمانی نشان ظاہر ہوتے ہیں اور اس کے ارادہ اور
مصلحت کے موافق دُعائیں قبول ہوتی ہیں اور غیب
کی باتیں بتلائی جاتی ہیں.اور حقائق اور معارف
قرآنی بیان فرمائے جاتے اور شریعت کے معضلات و مشکلات حل کئے جاتے ہیں اور مجھے اس
خدائے کریم و عزیز کی قسم ہے جو جھوٹ کا دشمن اور مفتری کا نیست و نابود کرنے والا ہے کہ میں اُس کی
Page 393
377
قرآن کریم کی معنوی محافظت
طرف سے ہوں اور اس کے بھیجنے سے عین وقت پر آیا ہوں اور اس کے حکم سے کھڑا ہوا ہوں.اور وہ
میرے ہر قدم میں میرے ساتھ ہے.اور وہ مجھے ضائع نہیں کرے گا اور نہ میری جماعت کو تباہی میں
ڈالے گاجب تک وہ اپنا تمام کام پورا نہ کرلے جس کا اُس نے ارادہ فرمایا ہے.اُس نے مجھے چودھویں
صدی کے سر پر تکمیل نور کے لئے مامور فرمایا.اربعین نمبر 2 روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 348)
ایک جگہ آپ مسلمانوں
کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں:
میں ہر ایک مسلمان کی خدمت میں نصیحاً کہتا ہوں کہ اسلام کے لئے جا گو کہ اسلام سخت فتنہ
میں پڑا ہے.اس کی مدد کرو کہ اب یہ غریب ہے اور میں اسی لئے آیا ہوں اور مجھے خدا تعالیٰ نے علم
قرآن بخشا ہے اور حقائق معارف اپنی کتاب کے میرے پر کھولے ہیں اور خوارق مجھے عطا کئے
ہیں.سو میری طرف آؤ تا اس نعمت سے تم بھی حصہ پاؤ.مجھے قسم ہے اس ذات کی جسکے ہاتھ میں
میری جان ہے کہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں.کیا ضرور نہ تھا کہ ایسی عظیم الفتن
صدی کے سر پر جس کی گھلی گھلی آفات ہیں ایک مجد دکھلے گھلے دعوئی کے ساتھ آتا.سوعنقریب
میرے کاموں کے ساتھ تم مجھے شناخت کرو گے ہر ایک جو خدا تعالیٰ کی طرف سے آیا اُسوقت کے
علماء کی نا مجھی اس کی سد راہ ہوئی.آخر جب وہ پہچانا گیا تو اپنے کاموں سے پہچانا گیا کہ تلخ درخت
شیریں پھل نہیں لاسکتا.اور خدا غیر کو وہ برکتیں نہیں دیتا جو خاصوں
کو دی جاتی ہیں.اے لوگو! اسلام
نہایت ضعیف ہو گیا ہے اور اعداء دین کا چاروں طرف سے محاصرہ ہے اور تین ہزار سے زیادہ مجموعہ
اعتراضات کا ہو گیا ہے.ایسے وقت میں ہمدردی سے اپنا ایمان دکھاؤ اور مردان خدا میں جگہ پاؤ.والسلام على من اتبع الهدى بركات الدعا روحانی خزائن جلد 6 صفحہ 36 )
حضرت مسیح موعود و مہدی معہود علیہ السلام نے اردو عربی اور فارسی زبانوں میں 83 سے زائد کتب اور بے شمار
اشتہارات اور خطوط تحریر کر کے تعلیم قرآن کریم کے فہم اور قرآنی معارف کی اشاعت کے لیے شائع کیے.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق قرآن کریم کا پیش فرمودہ ایمان دُنیا سے اٹھتے اٹھتے اس قدر
بلندی پر چلا گیا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں ثریا جتنا بلند ہو گیا.اسلام کا یہ بطل جلیل دوبارہ
ایمان کو آسمان سے اُتار لایا.آپ نے قرآن کریم کی تعلیمات کے خلاف جاری رسوم کا قلع قمع کیا اور امت مسلمہ
کے اُن عقائد کی اصلاح فرمائی جو قرآنی تعلیمات کے صریحاً خلاف تھے.آپ فرماتے ہیں:
منجملہ ان اُمور کے جو میرے مامور ہونے کی علت غائی ہیں مسلمانوں کے ایمان کو قومی کرنا ہے.اور انکوخدا اور اسکی کتاب اور اسکے رسول کی نسبت ایک تازہ یقین بخشنا.اور یہ طریق ایمان کے تقویت
کا دوطور سے میرے ہاتھ سے ظہور میں آیا ہے.اوّل قرآن شریف کی تعلیم کی خوبیاں کرنی اور اسکے
Page 394
الذكر المحفوظ
378
اعجازی حقائق اور معارف اور انوار اور برکات کو ظاہر کرنے سے جن سے قرآن شریف کا منجانب اللہ
ہونا ثابت ہوتا ہے.چنانچہ میری کتابوں کو دیکھنے والے اس بات کی گواہی دے سکتے ہیں کہ وہ کتابیں
قرآن شریف کے عجائب اسرار اور نکات سے پر ہیں اور ہمیشہ یہ سلسلہ جاری ہے اور اس میں کچھ شک
نہیں کہ جسقدر مسلمانوں کا علم قرآن شریف کی نسبت ترقی کریگا اسیقد رانکا ایمان بھی ترقی پذیر ہوگا.کتاب البریہ روحانی خزائن جلد 13 صفحہ 294 تا 297 حاشیہ )
اپنے مقام کی وضاحت کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں:
میری حیثیت ایک معمولی مولوی کی حیثیت نہیں ہے بلکہ میری حیثیت سُننِ انبیاء کی سی
حیثیت ہے.مجھے ایک سماوی آدمی مانو.پھر یہ سارے جھگڑے اور تمام نزاعیں جو مسلمانوں
میں پڑی ہوئی ہیں، ایک دم میں طے ہوسکتی ہیں.جو خدا کی طرف سے مامور ہو کر حکم بن کر آیا
ہے.جو معنے قرآن شریف کے وہ کرے گا وہی صحیح ہوں گے اور جس حدیث کو وہ صحیح قرار دے
گا وہی حدیث صحیح ہوگی.ایک اور جگہ آپ فرماتے ہیں:
( ملفوظات جلد اول صفحه 399 )
مجھے بتلایا گیا ہے کہ تمام دینوں میں سے دینِ اسلام ہی سچا ہے.مجھے فرمایا گیا ہے کہ تمام
ہدا ئتیوں میں صرف قرآنی ہدایت ہی صحت کے کامل درجہ پر اور انسانی ملاوٹوں سے پاک ہے.مجھے
سمجھایا گیا ہے کہ تمام رسولوں میں سے کامل تعلیم دینے والا اور اعلی درجہ کی پاک اور پُر حکمت تعلیم
دینے والا اور انسانی کمالات کا اپنی زندگی کے ذریعہ سے اعلیٰ نمونہ دکھلانے والا صرف حضرت
سید نا ومولانامحمد مصطفی ﷺ ہیں اور مجھے خدا کی پاک اور مطہر وحی سے اطلاع دی گئی ہے کہ میں
اس کی طرف سے مسیح موعود اور مہدی موعود اور اندرونی اور بیرونی اختلافات کا حکم ہوں.یہ
جو میرا نام مسیح اور مہدی رکھا گیا ان دونوں ناموں سے رسول اللہ ﷺ نے مجھے مشرف فرمایا اور پھر
خدا نے اپنے بلا واسطہ مکالمہ سے یہی میرا نام رکھا اور پھر زمانہ کی حالت موجودہ نے تقاضا کیا کہ یہی
میرا نام ہو.غرض میرے ان ناموں پر یہ تین گواہ ہیں.میرا خدا جو آسمان اور زمین کا مالک ہے
میں اس کو گواہ رکھ کر کہتا ہوں کہ میں اس کی طرف سے ہوں اور وہ اپنے نشانوں سے میری گواہی دیتا
ہے.اگر آسمانی نشانوں میں کوئی میرا مقابلہ کر سکے تو میں جھوٹا ہوں.اگر دعاؤں کے قبول ہونے
میں کوئی میرے برابر اتر سکے تو میں جھوٹا ہوں.اگر قرآن کے نکات اور معارف بیان کرنے میں
کوئی میرا ہم پلہ ٹھہر سکے تو میں جھوٹا ہوں.اگر غیب کی پوشیدہ باتیں اور اسرار جو خدا کی اقتداری
قوت کے ساتھ پیش از وقت مجھ سے ظاہر ہوتے ہیں ان میں کوئی میری برابری کر سکے تو میں خدا کی
Page 395
قرآن کریم کی معنوی محافظت
طرف سے نہیں ہوں.اسی طرح فرماتے ہیں:
379
اربعین روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 345-346)
میں یہ نہیں کہتا کہ پہلے نشانوں پر ہی ایمان لاؤ.بلکہ میں کہتا ہوں اگر میں حکم نہیں ہوں تو میرے
نشانوں
کا مقابلہ کرو.میرے مقابل پر جو اختلاف عقائد کے وقت آیا ہوں اور سب بحثیں لکھی ہیں.صرف حکم کی بحث میں ہر ایک کا حق ہے جس کو میں پورا کر چکا ہوں.خدا نے مجھے چار نشان دیتے ہیں.(1) میں قرآن شریف کے معجزہ کے ظل پر عربی بلاغت فصاحت کا نشان دیا گیا ہوں.کوئی نہیں کہ
جو اس کا مقابلہ کر سکے.(2) میں قرآن شریف کے حقائق و معارف بیان کرنے کا نشان دیا گیا ہوں.کوئی نہیں کہ جو
اس کا مقابلہ کر سکے.(3) میں کثرت قبولیت دعا کا نشان دیا گیا ہوں کوئی نہیں کہ جو اس کا مقابلہ کر سکے.میں حلفاً
کہہ سکتا ہوں کہ میری دعائیں تیس ہزار کے قریب قبول ہو چکی ہیں اور ان کا میرے پاس ثبوت ہے.(4) میں غیبی اخبار کا نشان دیا گیا ہوں.کوئی نہیں جو اس کا مقابلہ کر سکے.یہ خدا تعالی کی
گواہیاں میرے پاس ہیں اور رسول اللہ ﷺ کی پیشگوئیاں میرے حق میں چمکتے ہوئے نشانوں
کی طرح پوری ہوئیں.ضرورت الامام روحانی خزائن جلد 13 صفحہ 496-497)
خدا تعالیٰ برکات رسالت کو انبیاء کی وفات کے بعد بھی جاری رکھنے کے لیے قدرت ثانیہ یعنی خلافت کا مقدس سلسلہ
جاری فرماتا ہے.چنانچہ خلفاء راشدین کی محافظت قرآن شریف کے بارہ میں خدمات پر ایک اجمالی نظر ہم ڈال چکے
ہیں.اس قدرت ثانیہ کا ایک زندہ وجاوید نمونہ خلافت احمدیہ ہے.جو تم ریزی امام الزماں حضرت مسیح موعود و مہدی معہود نے
فرمائی تھی اس پودے کو مزید تناور کرنے اور کل عالم پر سایہ لیکن کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے آپ کے
بعد جماعت احمدیہ میں خلافت کا نظام جاری فرمایا.خدا تعالیٰ کے قائم کردہ خلفاء مسیح موعود علیہ السلام تعلیم القرآن کی اس مہم
کو پوری شان سے آگے بڑھا رہے ہیں اور حضرت مسیح موعود کی بعثت کے مقصد کو پورا فرمارہے ہیں.قرآن شریف کی معنوی حفاظت کے پہلو کے حوالہ سے دیکھا جائے تو خلافت احمدیہ نے ہمیشہ بنی نوع کی
جھولیاں بھری ہیں.خلافت احمدیہ کا طرہ امتیاز اپنے آقا و مطاع حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے
غلام کامل حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اسوہ حسنہ اور راہنمائی کے مطابق چلتے ہوئے تعلیم قرآن رہا ہے.خلفاء احمدیت کی ہر کاوش دین اسلام کا شرف اور کلام اللہ کا مرتبہ نیا پر ظاہر کرنے پر صرف ہوئی.ایک طائرانہ نظر
ان
کاوشوں پر ڈالتے جو براہ راست قرآن کریم کی معنوی حفاظت سے تعلق رکھتی ہیں.حضرت حکیم الحاج مولوی نور الدین خلیفہ امسیح الاول رضی اللہ عنہ کے درس ہائے قرآن ، تصانیف اور خطبات
Page 396
الذكر المحفوظ
380
سے مرتبہ تفسیری نکات اور معارف کا مجموعہ جو قرآن کریم کی معنوی حفاظت کے حوالہ سے آپ کی خدمت قرآن کا
زندہ و جاوید ثبوت ہے حقائق الفرقان“ کے نام سے چار جلدوں میں شائع شدہ ہے.اسی طرح آپ کے
مطبوعہ خطبات ، خطابات اور تقاریر وغیرہ معارف قرآن کا ایک نا در خزینہ ہیں.حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب خلیفہ اسیح الثانی الصلح الموعود رضی اللہ عنہ کی تمام زندگی کلام اللہ کا
مرتبہ ظاہر کرنے میں گزری.تفسیر کبیر، دیباچہ تفسیر القرآن ، فضائل القرآن اور بہت سی دیگر تفاسیر ناصرف اعجاز قرآنی
کا ایک ثبوت بلکہ فی ذاتہ اعجاز اور انسانی دسترس سے محض بالا الہامی مضامین سے پُر ہیں.قرآن کریم کی حفاظت
کے حوالہ سے امام الزمان کی اتباع کی برکات کا ذکر کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں:
اللہ تعالیٰ کے فضل سے میرا دعویٰ ہے کہ اس مامور کی اتباع کی برکت سے کسی علم کا متبع خواہ قرآن
کریم کے کسی مسئلہ پر حملہ کرے میں اس کا معقول اور مدلل جواب دے سکتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے
فضل سے ہر ذی علم کو ساکت کر سکتا ہوں خواہ وقتی جوش کے ماتحت وہ علی الاعلان اقرار کرنے کے
لئے تیار نہ ہو.میں نے اس کا ربع صدی سے زیادہ عرصہ میں تجربہ کیا ہے.میں سمجھتا ہوں کہ جب
سے اس میدان میں داخل ہوا ہوں، اللہ تعالیٰ کے فضل سے ظاہر و باطن میں کبھی مجھے اس بارہ میں
شرمندہ ہونے کا موقعہ نہیں ملا.( تفسیر کبیر جلد چہارم صفحه 52 زیر تفسیر الحجر آیت 10)
حضرت مرزا ناصر احمد صاحب
خلیفہ المسح الثالث رحمہ اللہ تعالیٰ حافظ قرآن بھی تھے اور خدا تعالیٰ کی طرف
سے قرآنی معارف کا خزانہ بھی.یوں آپ بھی حضرت خلیفہ اسیح الاول رضی اللہ عنہ کی طرح قرآن کریم کی
ظاہری حفاظت کے حوالہ سے اس سلسلہ سے تعلق رکھتے تھے جو خدا تعالیٰ نے صرف قرآن کریم کی حفاظت کی
خاطر ہی قائم کیا تھا اور جس کا پہلا سرا آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے یعنی حفظ قرآن کریم.اسی طرح معنوی
حفاظت کے حوالہ سے بھی آپ خدا تعالیٰ کے اُن چنیدہ سالاروں میں سے تھے جن پر خدا تعالیٰ خود اپنی کتاب کی
معنوی حفاظت کے لیے اس کے معارف آشکار کرتا چلا آیا ہے.آپ کے خطبات اور تقاریر يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ
وَالْحِكْمَةَ کے عظیم الشان ثبوت ہیں جو مختلف کتب اور اشتہارات کی زینت ہیں.برکات خلافت کے ضمن میں دور خلافت رابعہ میں بھی تعلیمات اور معارف قرآن کی بارش ویسی ہی آن بان
کے ساتھ جاری رہی.حضرت مرزا طاہر احمد صاحب خلیفتہ امسیح الرابع رحمہ اللہ کے خطبات جمعہ میں دقائق قرآن کا
ایک سمندر موجزن ہے.ان کے علاوہ دروس القرآن اور ترجمۃ القرآن کلاس ہر زمانہ کی طرح موجودہ زمانہ میں
بھی قرآن کریم کی ہردور میں اور ہر میدان میں راہنمائی مہیاء کرنے کی ایک دلیل اور اعجاز قرآنی کا ایک زندہ ثبوت ہے.حضرت خلیفہ اسیح الرابع رحمہ اللہ فرماتے ہیں:
یہ نہ سمجھیں کہ میں صرف آپ سے علم سیکھتا ہوں.اللہ تعالیٰ مسلسل آسمان سے مجھ پر علوم
Page 397
قرآن کریم کی معنوی محافظت
381
روشن فرماتا ہے اور وہ جو آسمان سے علم اترتے ہیں اس میں میرا اکتساب کوئی نہیں، یہ اللہ کا فضل
ہے.اور میں سمجھتا ہوں اس منصب کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک معمولی علم والے کو بھی چن کر
جب ایک منصب پر فائز فرما دیتا ہے تو علمی رہنمائی پھر خدا تعالیٰ اپنے ہاتھ میں لیتا ہے.خطبہ عید الفطر 3 مارچ 1995 بحوالہ الفضل سالانہ نمبر 30 دسمبر 2000 صہ 63)
خلافت کے منصب پر فائز ہونے کے بعد چونکہ آپ کا قیام زیادہ تر لندن میں رہا اس لیے اردو زبان کے
ساتھ ساتھ آپ نے انگریزی زبان میں بھی قرآن کریم کے معارف و معانی سے لبریز کتب شائع فرمائیں.مثلاً ایک
معروف کتاب Revelation Rationality Knowledge And Truth ہے.اس کے علاوہ خلفاء احمدیت
کی نگرانی میں بہت سی کتب آڈیو اور ویڈیو اور ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ کے ذریعہ تعلیم کتاب اور حکمت کے سلسلے میں
برکات خلافت تمام دُنیا میں پہنچ رہی ہیں نیز ساری دُنیا میں شائع ہونے والے بہت سے اخبارات اور رسائل
تعلیم کتاب اور حکمت کے باب کو ہر آن وار رکھتے ہیں.حضرت خلیفہ امسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز آج تعلیمات قرآن کی اشاعت میں جو بے انتہا محنت
اور مشقت اُٹھا رہے ہیں وہ اپنی مثال آپ ہے.اسی طرح آپ ( ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز ) کے ہزاروں ہزار
جانثار اپنی جانوں اور اپنے مالوں کے ساتھ آپ کے انصار میں شامل ہیں.یہ اسوہ بھی اپنی مثال آپ ہے.صرف تعلیم قرآن کے حوالہ سے ہی اس پاکیزہ وجود کی برکات چار دانگ عالم میں پھیلی ہوئی ہیں.آج دُنیا کا کوئی
گوشہ ایسا نہیں کہ جہاں یہ شریں آواز تشنہ روحوں کو سیراب اور مغموم دلوں کو مسرور نہ کر رہی ہو.معنوی حفاظت کا بہت زبردست ثبوت خدا تعالیٰ کے ایسے بندے ہیں جو قرآن کریم کی تعلیمات پر چل کر
وصال الہی کے مرتبہ تک پہنچتے ہیں اور دُنیا کے سامنے قرآن کریم کی صداقت کے عملی گواہ ہوتے ہیں.حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس پہلو کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں:
قرآن شریف کی حفاظت کا جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ توریت یا کسی اور کتاب کے
لیے نہیں اسی لیے ان کتابوں میں انسانی چالاکیوں نے اپنا کام کیا.قرآن شریف کی حفاظت کا
یہ بڑا ز بر دست ذریعہ ہے کہ اس کی تاثیرات کا ہمیشہ تازہ بتازہ ثبوت ملتا رہتا ہے اور یہود نے
چونکہ توریت کو بالکل چھوڑ دیا ہے اور ان میں کوئی اثر اور قوت باقی نہیں رہی جو ان کی موت پر
دلالت کرتی ہے.( ملفوظات جلد چہارم صفحہ 450)
حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:
پھر اس تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ جب تک قرآن کریم کی پیروی سے مجدد اور ماموراس
امت میں آتے رہیں گے یہ ثابت ہوتا رہے گا کہ قرآن کریم محفوظ ہے.کیونکہ ذکر کے ایک
Page 398
الذكر المحفوظ
382
معنے شرف اور نصیحت کے بھی ہیں.قرآن کریم کا نام ذکر اس لیے رکھا گیا کہ اس کے ذریعہ سے
اس کے ماننے والوں کو شرف اور تقویٰ حاصل ہوگا.پس اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إِنَّا لَهُ
لَحفِظُونَ میں اس طرف بھی اشارہ ہے.کہ یہ کلام جس کا یہ دعویٰ ہے کہ میرے ذریعہ سے
ماننے والوں کو شرف اور عزت اور تقویٰ ملے گا.ہمارا ہی اُتارا ہوا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ
ہیں یعنی ان صفات کو عملاً پورا کرنا ہمارا ہی کام ہے.اگر یہ صفات اس کی ظاہر نہ ہوں تو گویا اس
کی تعلیم ضائع ہوگئی.مگر ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے....غرض خدا تعالیٰ نے قرآن مجید کی معنوی حفاظت کا مدار صرف عقل پر ہی نہیں رکھا اور اس کی
تشریح کا انحصار صرف انسانی دماغ پر ہی نہیں چھوڑا.بلکہ خود اپنے کلام سے اس کو ظاہر فرمانے کا ذمہ
لیا ہے.جس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جب اس طرح سے عملی پھل ظاہر ہوتے ہیں تو قرآن مجید
کے محفوظ ہونے کا ایک بین ثبوت ملتا رہتا ہے.قرآن مجید کے تازہ پھل بھی ثابت کرتے رہتے
ہیں کہ قرآن مجید محفوظ اور زندہ کتاب ہے اور یہ قرآن مجید کی حفاظت کا ایساز بر دست ذریعہ ہے.جو اور کسی کتاب کو میسر نہیں اور نہ کبھی ہوگا.( تفسیر کبیر جلد چہارم صفحه 52 زیرتفسیر المجر آیت 10)
پس جیسا کہ یہ عملی پھل آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک سے لے کر تمام زمانوں میں ظاہر ہوتے رہے
اسی طرح آپ کے غلام کامل حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی معہود علیہ السلام اور آپ کے خلفاء کی
شکل میں قرآن کریم کی حفاظت کے ایک اتم اور اکمل ثبوت کے طور پر موجود ہیں.چنانچہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی
مسیح موعود علیہ السلام کی قائم فرمودہ جماعت میں آپ کے ہزاروں صحابہ اور جانثار قرآن کریم کی محافظت کے
تازہ بتازہ ثبوتوں کے طور پر مخالفین اسلام پر حجت تمام کرتے رہے ہیں.یہ پاک وجود خلفاء احمدیت کی سرکردگی
میں قرآن کریم کی معنوی حفاظت کو یقینی بنائے ہوئے ہیں.آج بھی ایک پاکیزہ نورانی چہرہ ایسے لوگوں کی بڑی
جماعت کو اپنی حفاظت کے حصار اور اپنے جلو میں لیے اہل اسلام کو مسرور کر رہا ہے.اللهم ايد امامنا بروح القدس و كن معه حيث ما كان وانصره نصراً عزيزاً
اے اللہ ہمارے امام کی روح القدس سے تائید فرما اور وہ جہاں بھی ہوں اُن کے ساتھ ہو جا اور ان کی غالب مددفرما
اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم و
اے اللہ جو دین محمد مے کے انصار میں شامل ہو تو اس کا مددگار بن جا اور ہمیں اُن خوش نصیبوں میں سے بنا اور
اخزل من خزل دین محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم
جود بین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بُرا چاہے تو اسے ناکام و نامراد کر دے اور ہمیں ایسے لوگوں میں سے نہ بنانا.(آمین)
Page 399
قرآن کریم کی معنوی محافظت
383
مسئله ناسخ و منسوخ
دُنیا کے عام قانون دان یا قانون ساز ادارے جو مہذب معاشرہ کے لیے قوانین سازی کرتے ہیں، آئے دن
اپنے قوانین پر نظر ثانی کرتے اور تجربات اور مشاہدات کی روشنی میں غلطیوں کی اصلاح اور رد و بدل کرتے رہتے
ہیں.قرآن کریم بھی دستور حیات ہے لیکن یہ کسی ایسے قانون کی طرح نہیں جو انسان نے بنایا ہو.اس کا دعوی ہے
کہ یہ خدا تعالیٰ کا پیش فرمودہ ہے.پس اگر یہ واقعی خدا کا کلام ہے تو پھر اس میں کسی نظر ثانی کی گنجائش نہیں ہے.الہی قانون
میں تبدیلی ناممکن ہے ورنہ اعتراض پیدا ہوتے کہ کیا خدا تعالیٰ کو بھی نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا خدا تعالیٰ کو
بھی بیان بدلنے کی ضرورت پڑتی ہے.اگر ایساہے تو پھر یہی نتیجہ نکلتاہے کہ گویا خدا تعالی بھی غلطی سے پاک نہیں
ہے.اگر خدا تعالیٰ علیم اور قدوس ہے یعنی ہر علم پر کامل طور سے محیط اور ہر غلطی اور عیب سے منزہ ہے تو پہلی دفعہ ہی
درست اور حتمی بات کرتا اور بار بار بات بدلنے کی ضرورت نہ پڑتی.کیونکہ نظر ثانی کی ضرورت تو وہاں پڑتی ہے
جہاں غلطی کا امکان ہو.اگر خدا غلطی کر سکتا ہے تو پھر نظر ثانی کر کے اپنی بات کو بدل سکتا ہے.اگر غلطی نہیں کرتا تو
پھر بدلنے کا سوال ہی نہیں.پس اگر خدا تو غلطی نہیں کرتا لیکن قرآن مجید میں ہمیں ایسے بیانات ملتے ہیں جو ایک
دوسرے کو رڈ کرتے ہیں یا ایک دوسرے کے خلاف ہیں اور یہ ایک ایسا کلام ہے کہ متضاد ہونے کی وجہ سے ایک
حصہ دوسرے کو منسوخ کرتا ہے تو پھر یہ خدا کا کلام نہیں ہوسکتا.کیونکہ عقل یہ تسلیم نہیں کرتی کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں
یا اس کے قول اور فعل میں تضاد ہو سکتا ہے.چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یہی اصول بیان
فرماتا ہے:
لَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيْهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا (النساء: 83)
اگر (یہ قرآن) غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت اختلاف ہوتا.مگر بد قسمتی سے پھر بھی مسلمانوں نے واضح ہدایت اور راہنمائی کے باوجود اس قسم کی غلطی کی اور اس اصول کو
کلیہ رد کرتے ہوئے قرآن کریم کی بعض آیات کو بعض دوسری آیات کے متضاد سمجھ کر منسوخ قرار دے دیا اور یوں
عامتہ المسلمین کو بھی اپنے مذہب کے بارے میں شکوک میں مبتلا کیا اور مخالفین کوبھی اعتراضات کا موقع دیا.قرآن کریم
کے بارہ میں مسلمانوں میں جو غلط فہمیاں پیدا ہو چکی ہیں ان میں سے ایک غلط نہی نسخ فی القرآن کا عقیدہ ہے.نسخ
کے عقیدہ کا براہ راست قرآن کریم کی معنوی حفاظت سے تعلق ہے.اگر قرآن کریم میں نسخ کا جواز تسلیم کیا جائے تو
پھر قرآن کریم محفوظ تسلیم نہیں کیا جاسکتا کیونکہ پھر یہ جھگڑا کھڑا ہو جاتا ہے کہ کون سی آیت منسوخ ہے اور کون سی
نہیں.ہر شخص اپنے فہم کے مطابق قرآنی آیات کو رڈ کرنے لگے گا.
Page 400
الذكر المحفوظ
384
پس قرآن
کریم کی معنوی محافظت کے ضمن میں مناسب ہے کہ ناسخ منسوخ کے مسئلہ پر بھی ایک مختصر نظر ڈالی جائے.مستشرقین اور مغربی محققین بھی حفاظت قرآن کریم کے پہلو پر حملہ کرنے کے لیے نسخ کے عقیدہ کو سہارا بناتے
ہیں.چنانچہ ابن وراق نے بھی قرآنِ کریم کی عدیم النظیر حفاظت کے پہلو پر اعتراض کرنے کے لیے عقیدہ نسخ کا
سہارا لیا ہے.کہتا ہے:
The doctrine of abrogation also makes a mockery of
the Muslim dogma that the Koran is a faithful and
unalterable reproduction of original scriptures that are
preserved in Heaven.If God's words being superseded
or becoming obsolete? Are some words of God to be
preferred to other words of God? Apparently yes.According to Muir, some 200 verses have been canceled
by later ones.Thus we have the strange situation where
the entire Koran is recited as the word of God, and yet
there are passages that can be considered not "true"; in
other words, 3 percent of the Koran is acknowledged as
falsehood.(Ibn Warraq: Why I am Not A Muslim, Prometheus Books, New
York, 1995, under heading; The Koran: Pg: 115)
کیا نسخ کا عقیدہ بھی اس اسلامی عقیدہ کا تمسخر نہیں اُڑا تا کہ قرآن کریم لوحِ محفوظ کی دیانت
داری اور اخلاص سے کی گئی نا قابل تحریف نقل بمطابق اصل ہے.کیا خدا کے بعض اقوال
پُرانے اور فرسودہ ہیں؟ کیا خدا کے بعض احکام بعض دوسرے احکام سے زیادہ اہم ہیں؟ (اس
عقیدہ کے مطابق ) بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے.میور کے مطابق لگ بھگ دوسو آیات بعد میں نازل
ہونے والی آیات سے منسوخ ہوئیں ہیں.اب ہم عجیب مخمصہ میں ہیں کہ ایک طرف تو سارے
قرآن کریم کی بطور کلام الہی تلاوت کی جاتی ہے جبکہ اس میں ایسے حصے بھی ہیں جو کہ حق نہیں
ہیں.با الفاظ دیگر قرآن کریم کا ایک تہائی حصہ مسلمہ طور پر باطل ہے.اس ضمن میں ایک بات تو یہ مد نظر رہی چاہیے کہ نسخ کا عقیدہ اگر درست بھی تسلیم کر لیا جائے تو بھی قرآن کریم
کی لفظی حفاظت کے بارہ میں کوئی شبہ پیدا نہیں ہوتا.کیونکہ یہ حقیقت بہر حال تسلیم شدہ ہے کہ قرآن کریم جس
صورت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے بنی نوع کو عطا ہوا بعینہ اسی طرح محفوظ ہے.چنانچہ میور
کی گواہی درج کی جاچکی ہے کہ قرآن کریم بلا تحریف و تبدل ہم تک پہنچا ہے.ہاں معنوی حفاظت کے پہلو کے
لحاظ سے قرآن کریم میں ناسخ و منسوخ
کو تسلیم نہیں کیا جاسکتا.این وراق درست کہتا ہے کہ قرآن کریم میں خدا کا بیان فرمودہ ایک ایک حرف حتمی ، درست اور قابل عمل ہے
Page 401
قرآن کریم کی معنوی محافظت
385
اور پرانا اور فرسودہ نہیں ہے اور اس میں بیان شدہ کوئی لفظ غیر اہم نہیں ہے.اگر کوئی مسلمان یہ کہتا ہے کہ قرآن کریم
میں کوئی لفظ منسوخ ہے تو وہ غلط کہتا ہے! قرآن کریم کلام الہی ہے اور اس کا ایک شعشہ بھی منسوخ نہیں اور ہر ایک
حرف جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا بر حق اور رہتی دنیا تک کے لیے راہنمائی ہے اور اسی طرح قابل عمل
ہے جیسا کہ بوقت نزول قابل عمل تھا.گو عام طور پر مسلمان
علماء نسخ فی القرآن کے قائل ہیں لیکن آئمہ جب نسخ کی
بات کرتے ہیں تو صرف یہ مراد ہوتی ہے کہ قرآن کریم کی آیت کے جو معنی ہم کیا کرتے تھے ان معانی کا غلط ہونا
فلاں آیت کے نزول سے ثابت ہو گیا ہے.پس سخ سے مراد شیخ معانی تھا.گویا نسخ سے مراد یہ تھی کہ ہماری نظر میں
اس آیت کے جو معنی ہیں دوسری آیت اُن معنی کو درست قرار نہیں دیتی.حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں:
ہم پختہ یقین کے ساتھ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ قرآن شریف خاتم کتب و ماوی ہے
اور ایک شعشہ یا نقطہ اس کی شرائع اور حدود داورا حکام اور اوامر سے زیادہ نہیں ہوسکتا اور نہ کم ہوسکتا
ہے اور اب
کوئی ایسی وحی یا ایسا الہام منجانب اللہ نہیں ہو سکتا جو حکام فرقانی کی ترمیم یا تنسیخ یا کسی
ایک حکم کے تبدیل یا تغییر کرسکتا ہو.(ازالہ اوہام روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 170 )
ابن وراق کے لیے تو اتنا جواب کافی ہے لیکن اپنے باقی مسلمان بھائیوں کے لیے ہمدردی اور محبت کے جذبات
کے ساتھ عرض ہے کہ ایک طرف تو آپ قرآن کریم کو کلام الہی تسلیم کرتے ہیں اور دوسری طرف اس میں ایسے نسخ کے
قائل ہیں کہ گویا قرآن کریم میں ایک آیت نازل ہوتی تھی پھر وہ کالعدم ہوجاتی تھی.یہ دو متضاد عقائد کیونکر اکٹھے
ہو سکتے ہیں؟ ایسا عقیدہ رکھنے سے عقل و خرد کو خیر آباد کہنا پڑتا ہے.خاص کر اس صورت میں تو بالکل ہی اس عقیدہ کو چھوڑنا
پڑتا ہے کہ جب یہ علم ہوتا ہے کہ قرآن کریم اس عقیدہ کو رد کرتا ہے اور کسی صحیح حدیث میں آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم
قرآن کریم میں نسخ کا ذکر نہیں فرماتے اور نہ ہی صحابہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فلاں آیت کو
فلاں آیت سے منسوخ قرار دیتے تھے.ذیل میں ہم نسخ فی القرآن کے قائلین کے عقیدہ کا مختصر تجزیہ کرتے ہیں:
قرآن کریم میں نسخ کو جائز سمجھنے والے ایک دلیل اس آیت سے پیش کرتے ہیں:
مَا نَفْسَخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ تُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى
كُلَّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.(البقره: 107)
ترجمہ: جو آیت بھی ہم منسوخ کر دیں یا اُسے بھلا دیں ، اُس جیسی یا اُس سے بہتر ضرور لے
آتے ہیں.کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ ہر چیز پر جسے وہ چاہے دائمی قدرت رکھتا ہے؟
اس سے یہ مطلب اخذ کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قرآن کریم کی کوئی بھی آیت میں منسوخ کر دیتا ہوں
Page 402
الذكر المحفوظ
386
مگر جب منسوخ کرتا ہوں تو بعینہ ویسی یا اس سے بھی بہتر آیت لے آتا ہوں.حالانکہ یہاں تو قرآنی آیات کا
ذکر ہی نہیں ہورہا.یہاں تو یہود کا ذکر ہورہا ہے.پس ایسی بے تعلق بات کو دلیل کے طور پر پیش کیا جارہا ہے جس کا
سارے قصہ سے تعلق ہی کوئی نہیں.اصل میں تو یہ قصہ چل رہا ہے کہ یہود نہیں چاہتے کہ تم پر کوئی خیر نازل ہو.مگر تم
پر اللہ نے قرآن نازل کیا.اب یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ قرآن کے نزول کی ضرورت کیا ہے جبکہ پہلے سے ہی
الہی تعلیمات اور کتب موجود ہیں.اس کا جواب یہ آیت دے رہی ہے کہ ان کتب کے بعض حصے اس قابل تھے کہ
منسوخ کر دیے جاتے اور بعض ایسی باتیں تھیں کہ مرورِ زمانہ سے لوگوں کو بھول گئی تھیں اور آہستہ آہستہ کتب سماویہ
سے محو ہو گئی تھیں.ان
کا دوبارہ بیان کرنا ضروری تھا.پس ایک حصہ کو ہم نے منسوخ کردیا اور اس سے بہتر تعلیم اس
کتاب میں بیان کر دی اور وہ تعلیم جو بھول گئی تھی اس کو پھر اسی طرح بیان کر دیا اور اہل کتاب اس پر اعتراض نہیں
کر سکتے کیونکہ خود ان کی کتابوں میں نئی شریعت کی خبر موجود ہے.چنانچہ یرمیاہ باب 31 آیت 31 میں ہے:
”دیکھ وے دن خداوند کہتا ہے میں اسرائیل کے گھرانے اور یہود کے گھرانے کے ساتھ نیا
عہد باندھوں گا.اس عہد کے موافق نہیں جو میں نے اُن کے باب دادا سے کیا
پس قائلین نسخ اس آیت سے نسخ فی القرآن کا جو عقیدہ اخذ کرتے ہیں وہ سیاق وسباق کی رو سے غلط ٹھہرتا
ہے.مضمون کوئی اور بیان ہو رہا ہے اور مطلب کچھ لیا جارہا ہے.پس عقیدہ نسخ کی بنیادہی نا کبھی پر ہے.اس غلط تفہیم پر بنیا در کھتے ہوئے علما نسخ کی تین اقسام بیان کرتے ہیں.ان کے نزدیک :
ا.شیخ کی ایک قسم یہ ہے کہ آیت کے معنی تو قائم ہوتے ہیں مگر الفاظ مہو کر دیے جاتے ہیں.گویا ایک
آیت معنا تو قرآن کریم میں موجود ہوتی ہے مگر اس کے الفاظ اس میں نہیں ہوتے.وہ اس کی ایک
مثال یہ بتاتے ہیں کہ قرآن کریم میں پہلے یہ آیت کہ الشیخ والشيخوخة اذا زنـيـا فـارجــمـوهـما
نكالا من الله والله عزيز حكيم.-۲.دوسری قسم کا نسخ یہ بتاتے ہیں کہ آیت کے الفاظ تو قائم رکھے جاتے ہیں مگر اس کا حکم منسوخ کر دیا جاتا
ہے.اس کے ثبوت میں ایک آیت لا اکراہ فی الدین پیش کرتے ہیں.اس
قسم کا نسخ قرآن کریم
میں بہت زیادہ تسلیم کیا گیا ہے..تیسری قسم کا نسخ وہ ہوتا ہے جس میں ان کے نزدیک آیت کے الفاظ اور معنی دونوں منسوخ ہو جاتے
ہیں.اس کی مثال
وہ تحویل قبلہ کا حکم بتاتے ہیں.ننسها سے مراد وہ لیتے ہیں کہ متعلقہ حصہ ذہنوں سے اتر جاتا ہے اور اس کے ثبوت میں ایک من گھڑت
قصہ پیش کرتے ہیں جس کا ذکر آگے آئے گا.
Page 403
387
قرآن کریم کی معنوی محافظت
قرآن کریم کے نسخ کے عقیدہ پر قائم لوگ اس بارہ میں کوئی ایسی دلیل پیش نہیں کرتے کہ رسول کریم صلی اللہ
علیہ والہ وسلم نے فرمایا ہو کہ فلاں آیت منسوخ ہے.یہ بہت حیرت کی بات ہے کہ قرآن کریم میں اتنی کثرت
سے ناسخ منسوخ موجود ہو لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بارہ میں کوئی رہنمائی نہ فرما ئیں.پس قائلین نسخ
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہنمائی کے بغیر محض استدلال کرتے ہیں جس میں ان کی اپنی سوچ کارفرما ہوتی
ہے.اور یہ استدلال قرآن کریم کے معانی کے عدم فہم یا عدم علم کی وجہ سے ہوتا ہے.اس میں کوئی شک نہیں کہ وقتی احکام اور شرائع منسوخ ہوتی ہیں.مگر قرآن کریم جو کہ ایک دائمی شریعت ہے
اس کی طرف اس یہ بات منسوب کرنا واقعی معیوب ہے.پھر اس سے بڑھ کر معیوب بات یہ ہے کہ کوئی شخص
قرآن کریم کے بارہ میں یہ عقیدہ رکھے کہ اس میں بعض الفاظ تو موجود ہیں مگر وہ قابل پیروی نہیں کیوں کہ منسوخ
ہیں اور اپنے اس قول کی تائید میں کوئی وحی پیش نہ کرے بلکہ اپنا قیاس پیش کرے.اس سے گمراہی کا بہت بڑا
خطرہ پیدا ہو جاتا ہے اور قرآن کریم کا کوئی اعتبار باقی نہیں رہتا.پس قرآن کریم کی اس آیت میں عموماً مفسرین غلطی کھاتے ہیں جو یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ جو آیت اللہ نے قرآن کریم
میں اتاری ہے وہ منسوخ بھی ہوسکتی ہے اور ہم اس سے بہتر آیت لا سکتے ہیں.اس کے نتیجہ میں ناسخ منسوخ کا بہت
لمبا جھگڑا چل پڑا.مفسرین نے تقریبا پانچ سو آیات کو ناسخ اور پانچ سو آیات کو منسوخ قراردے دیا.حالانکہ قرآن کریم
کا ایک شعشہ بھی منسوخ نہیں.حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے پہلے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے وقت تک
یہ ساری ناسخ و منسوخ آیات حل ہو چکی تھیں سوائے پانچ کے اور حضرت مسیح موعود کے علم کلام کی برکت سے یہ پانچ
آیات بھی حل ہو گئیں.جماعت احمدیہ کا عقیدہ ہے کہ قرآن کریم کا ایک شععہ بھی منسوخ نہیں.یہاں آیت سے
مراد پہلی شریعتیں ہیں جب بھی وہ منسوخ ہوئیں یا بھلا دی گئیں تو ویسی ہی یا اُن سے بہتر نازل کر دی گئیں.انسانی دماغ کے کئی مدارج ہیں.بعض دماغ ایک بات کو سمجھتے ہیں اور بعض نہیں سمجھتے.اگر انسانی دماغ کی
سمجھ پر اس بات کی بنیا د رکھی جائے کہ کون سی آیت منسوخ ہے اور کون سی آیت منسوخ نہیں تو ایک لحاظ سے سارا
قرآن ہی منسوخ ماننا پڑے گا کیوں کہ کسی حصہ کو کوئی نہیں مانتا اور کس کو کوئی نہیں مانتا.جس کی سمجھ میں سو آیات نہ
آئیں اس نے سومنسوخ قرار دے دیں اور جس کی سمجھ میں ہزار نہ آئیں اس نے ہزار آیات منسوخ قراردے
دیں.چنانچہ اس کی امر مثال کہ بعض آیات کو اس لیے منسوخ کہا جاتا ہے کہ وہ بظاہر دوسری آیات کے مخالف نظر
آتی ہیں ، ہم مولوی مودودی کے الفاظ میں بیان کرتے ہیں: آپ رقم طراز ہیں:
لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ (البقرة: 257 )
یعنی دین میں جبر نہیں مگر اس واضح آیت کے ہوتے ہوئے بھی بعض مسلمان دین میں جبر کو
Page 404
الذكر المحفوظ
388
جائز سمجھتے ہیں.ان کے نزدیک بعد میں نازل ہونے والی جہاد کی آیات نے یہ آیت منسوخ
کر دی ہے.اگر اس منسوخ نہ کہا جائے تو تضاد پیدا ہوتا ہے قرآن میں.سید ابوالاعلیٰ مودودی ارتداد کی سزا اسلامی قانون میں صہ 53,54 زیر عنوان عقل اور
قتل مرتد بار اوّل جون 1951 ء مرکزی مکتبہ جماعت اسلامی اچھرہ پاکستان )
جبکہ قرآن کریم یہ نہیں کہتا کہ قرآن کی دو آیات میں تضاد ہو تو ایک آیت کو منسوخ قراردے دو بلکہ خدا تعالیٰ تو
فرماتا ہے کہ اگر تضاد ہو تو سمجھو کہ قرآن کریم خدا کی طرف سے ہے ہی نہیں بلکہ خدا کے سوا کسی کی طرف سے
ہے.چنانچہ فرمایا:
لَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيْهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا (النساء: 83)
اگر یہ قرآن اللہ کو چھوڑ کو اوروں کی طرف سے ہوتا تو وہ اس میں بہت اختلاف پاتے.تاریخ اسلام میں بہت کثرت سے احادیث درج ہیں جن میں آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر قرآن
بالقرآن کے بارہ میں ارشاد فرمایا ہے.مثلاً :
حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ جَدِّهِ قَالَ لَقَدْ جَلَسْتُ أَنَا وَأَخِي مَجْلِسًا مَا أُحبُّ أَنَّ لي به حُمْرَ
النعم أَقْبَلْتُ أَنَا وَأَخِي وَإِذَا مَشْيَحَةٌ مِنْ صَحَابَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُلُوسٌ عِنْدَ بَاب مِنْ أَبْوَابه فَكَرِهْنَا أَنْ نُفَرِّقَ بَيْنَهُمْ فَجَلَسْنَا
حَجْرَةً إِذْ ذَكَرُوا آيَةً مِنْ الْقُرْآن فَتَمَارَوْا فِيهَا حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمْ
فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُغْضَبًا قَدْ احْمَرَّ وَجْهُهُ يَرْمِيهِمْ
بالتُّرَابِ وَيَقُولُ مَهْلًا يَا قَوْمِ بِهَذَا أُهْلَكَتْ الْأُمَمُ مِنْ قَبْلِكُمْ بِاخْتِلَافِهِمْ
أَنْبَيَائِهِمْ وَضَرْبِهِمْ الْكُتُبَ بَعْضَهَا بِبَعْضٍ إِنَّ الْقُرْآنَ لَمْ يَنْزِلُ يُكَذِّبُ
بَعْضُهُ بَعْضًا بَلْ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضًا فَمَا عَرَفْتُمْ مِنْهُ فَاعْمَلُوا بــه وَمَـ
جَهِلْتُمْ مِنْهُ فَرُدُّوهُ إِلَى عَالِمه
مسند احمد بن حنبل مسند المكثرين من الصحابة حديث: 6415
وَمَا
حضرت انس بن عیاض کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کسی مجلس
میں تشریف فرما تھے.اُنہوں نے قرآن کریم کی ایک آیت کا تذکرہ کیا جس میں اُن کا آپس
میں اختلاف ہو گیا اور آواز میں بلند ہوگئیں.اس پر آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے
آئے.آپ کا چہرہ شدت غضب سے سُرخ تھا.آپ نے ناراضگی سے
فرمایا اے میری قوم
Page 405
389
قرآن کریم کی معنوی محافظت
اس قسم کے معاملات میں نہ پڑو تم سے پہلی امتیں انبیاء اور اُن کی کتب میں تقابل کر کے اُن
کے بارہ میں اختلاف کی وجہ سے ہلاک ہوئیں ہیں.قرآن کریم اس طرح تو نازل نہیں ہوا کہ
اس کا ایک حصہ دوسرے کو جھٹلائے بلکہ اس کا ایک حصہ دوسرے کی تصدیق کرتا ہے.پس (اس
اصول کو راہنما بناتے ہوئے ) جو سمجھ آئے اس کے مطابق عمل کرو اور جو سمجھ نہ آئے تو اُس سے
پوچھ لیا کرو جو اس معاملہ میں اہل علم ہو.پس آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کو راہنما بناتے ہوئے ہمیں قرآن کریم کی وہی تفسیر کرنی چاہیے جو
قرآن کریم کی دوسری آیات کے مطابق ہو نہ کہ اپنی مرضی کے معانی کر کے اُن تمام آیات کو منسوخ قرار دیدینا
چاہیے جو ہمارے کیے ہوئے معانی کو رڈ کرتی ہوں.اگر کسی آیت کے معانی قرآن کریم کی دوسری آیات کے خلاف
ہوں تو لازمی نتیجہ یہی ہوگا کہ وہ معانی غلط ہیں کیونکہ قرآن تضاد سے پاک ہے.پس درست معانی سمجھنے کی کوشش کرنی
چاہیے اور اگر نہ سمجھ آئیں تو اہل علم سے رجوع کرنا چاہیئے.کسی آیت کو مکمل طور پر نا سمجھنے کی صورت میں یہ نتیجہ نہیں
نکالا جاسکتا کہ وہ آیت منسوخ ہے اور نہ ہی کوئی شخص یہ دعوی کر سکتا ہے کہ وہ سب
قرآن سمجھ چکا ہے پس نا مجھی پر
کیسے ایک عقیدے کی بنیاد رکھی جاسکتی ہے.حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب خلیفتہ امسیح الثانی فرماتے ہیں:
اللہ تعالی نے انسانوں میں بڑے بڑے علم والے لوگ پیدا کیے ہیں مگر کوئی نہیں کہ سکتا کہ
میں نے سارا علم قرآن حاصل کر لیا ہے.میں بھی کہ جس پر اللہ نے قرآن کریم کے بے شمار
معارف کھولے ہیں نہیں کہہ سکتا کہ قرآن کریم کا سارا علم میں نے حاصل کر لیا ہے اگر ایسا ہوتا
کہ کوئی شخص اس کے تمام معارف سمجھ لیتا تو قیامت آجاتی.کیونکہ قرآن کریم قیامت تک کے
لیے ہے اور اس کے بعد اور کوئی کتاب نہیں.جب اس میں سے نئے نئے مضامین نکلنے بند
ہوجائیں گے اس وقت قیامت آجائیگی.پس اس کے معارف کبھی ختم نہیں ہو سکتے اور یہ کتاب
ہمیشہ نئے نئے مطالب دنیا میں ظاہر کرتی رہے گی.( تفسیر کبیر جلد دوم صہ 98-97)
قائلین نسخ کی یہ گستاخی بہت عجیب ہے کہ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ ایک چھوڑ ایک کروڑ احادیث بھی قرآن
کریم کی کوئی آیت منسوخ نہیں کر سکتیں لیکن دوسری طرف اپنے ظن سے قرآن کی آیات کو منسوخ قرار دیتے
ہیں اور اپنی سوچ کا مرتبہ احادیث رسول سے بھی بڑا سمجھتے ہیں کہ گویا انہیں تو یہ حق حاصل ہے کہ کچھ آیات کو
منسوخ قرار دے دیں لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حق حاصل نہیں.یہ ایسی بات ہے کہ ہر عقل مندا سے
تسلیم کرنے سے انکار کر دے گا.
Page 406
الذكر المحفوظ
390
پس قرآن کریم کی آیات کے معنے اور تفسیر کرنے کا ایک بہت بنیادی اصول اور ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ
قرآن کریم کی آیات کے معنی قرآن کریم کی دوسری آیات کے مطابق کیے جائیں.قرآن کریم آیات کے وہ معنی
کرنے چاہئیں جو کہ تمام آیات کے مطابق ہوں اور یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اپنی مرضی سے ایک آیت کے معنی کر لیے
اور باقی آیات کو منسوخ قرار دے دیا.یہ منشاء الہی اور منشاء رسول کے خلاف ہے.آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ
تو نہیں فرمایا کہ القرآن ينسخ بعضه بعضا
سوال یہ ہے اگر در حقیقت قرآن کریم میں کوئی آیت منسوخ نہیں ہے تو پھر کیوں بعض صحابہ نے بعض آیات کو
منسوخ قرار دیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ صحابہ اگر یہ لفظ استعمال کرتے تھے تو کسی قرآنی آیت کے منسوخ ہونے
کے بارہ میں نہیں بلکہ اس کے عام رائج معنی کے منسوخ ہونے کے کرتے تھے کہ ئی نازل ہونے والی آیت نے
پہلے سے نازل شدہ اس آیت کی تفسیر کر دی ہے اور جو معنی ہم سمجھتے تھے وہ معانی منسوخ ہو گئے ہیں.حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس بارہ میں رہنمائی کرتے ہوئے فرماتے ہیں:
قائلمین شیخ کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ حقیقی اور واقعی طور پر حدیث سے آیت منسوخ ہو جاتی
ہے بلکہ وہ لکھتے ہیں کہ واقعی امر تو یہی ہے کہ قرآن پر نہ زیادت جائز ہے اور نہ نسخ کسی حدیث
سے لیکن ہماری نظر قاصر میں جو استخراج مسائل قرآن سے عاجز ہے یہ سب باتیں صورت پذیر
معلوم ہوتی ہیں اور حق یہی ہے کہ حقیقی سخ اور حقیقی زیادت قرآن پر جائز نہیں کیونکہ اس سے اس
کی تکذیب لا زم آتی ہے.الحق مباحثہ لدھیانہ روحانی خزائن جلد 4 صفحه 93-92)
پس نہ تو وحی الہی سے کوئی آیت کبھی منسوخ قرار دی گئی اور نہ ہی معانی سمجھ نہ آنے سے کوئی آیت منسوخ سمجھی
جاسکتی ہے.اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی وحی الہی سے کسی آیت کے منسوخ ہونے کا علم ہوتا یا آپ کا یہ
منشاء ہوتا کہ معنوں کو دیکھ کر بظاہر متضاد آیات منسوخ قرار دے دی جائیں تو پھر لازمی تھا کہ جس طرح قرآن کریم
کی آیات کی نزول کے ساتھ ہی اشاعت کی جاتی تھی اسی طرح آنحضور وحی الہی سے منسوخ ہونے والی آیات کی
بھی سب صحابہ کو اطلاع کیا کرتے اور تاریخ میں ایسے واقعات محفوظ رکھے جاتے.امت نے یہ واقعات تو محفوظ کر لیے
جن میں آنحضور نے تفسیر القرآن بالقرآن کی تاکید فرمائی لیکن آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے ناسخ ومنسوخ
کا ایک بھی واقعہ محفوظ نہ کیا.عاقل را اشارہ کافی است!
پس قرآن کریم کی تفسیر کے لیے یہ بنیادی اصول آنحضور صلی علیہ وسلم نے معین فرما دیا ہے کہ قرآن کریم کی
آیات کے وہی معنی ہوں گے جو قرآن کریم کی دوسری آیات کے مطابق ہوں گے.اگر کسی آیت کے ایسے معانی
Page 407
قرآن کریم کی معنوی محافظت
391
کیے جائیں جو قرآن کریم کی دوسری آیات کے خلاف ہوں تو وہ معنی غلط ہوں گے.اگر تفسیر قرآن کے لیے
آنحضور کے بیان فرمودہ اس بنیادی اصول کو تسلیم نہ کیا جائے اور نسخ فی القرآن کا عقیدہ تسلیم کر لیا جائے تو
قرآن کریم کا وجود ہی بیکار ہو جاتا ہے اور امن اُٹھ جاتا ہے.ہر شخص اپنی مرضی سے معنے کرے گا.مثلاً اگر نسخ کا
قائل دین میں جبر کا قائل ہوگا تو پھر تو ایک آفت آجائے گی.ایسا شخص قرآن کریم سے وہ تمام آیات منسوخ قرار
دیدے گا جن میں یہ ذکر ہے کہ اپنے لیے مذہب کا انتخاب کرنا انسان کا ایسا ذاتی فعل ہے جس کا تعلق خدا تعالیٰ سے
ہے.دلائل کی روسے بچے دین کی تلاش تو ہو سکتی ہے لیکن کوئی شخص جبراً کسی دوسرے شخص کو اپنے دین میں نہیں
داخل کر سکتا اور نہ ہی کسی دین سے نکال سکتا ہے.چنانچہ ایسا شخص اگر طاقتور ہو تو ظلم اور تعدی کی راہ سے دُنیا کا امن
برباد کر دے گا اور صرف اُن لوگوں کو زندہ رہنے کا حق دے گا جو اس کے دین کے مطابق اپنا دین بنائیں گے.ایک بات یہ بھی مد نظر رہے کہ موجودہ قرآن کریم پر صحابہ کا دومرتبہ اجماع ہوا تھا.ایک دفعہ حضرت ابوبکر
کے دور میں اور ایک مرتبہ حضرت عثمان کے دور میں.پس جب صحابہ کا سارے قرآن کریم پر اتفاق ہے تو کوئی
آیت کسی ایک صحابی کے کہنے پر منسوخ قرار نہیں دی جا سکتی.ایک طرف تو تمام صحابہ اس آیت کو قرآن کریم کا
حصہ قرار دیتے ہیں اور دوسری طرف ایک صحابی کسی آیت کو منسوخ مانتا ہے تو ہزاروں صحابہ کے اجماع کے خلاف
اُس ایک صحابی کی رائے کی کیا وقعت ہو سکتی ہے؟ اگر تمام صحابہ نے بالاتفاق یہ شہادت دی ہو کہ یہ آیت قرآن کریم
میں شامل ہے اور پھر اسی اتفاق کے ساتھ بیان نہ کیا ہو کہ یہ آیت منسوخ ہے تو محض ایک یا دو صحابہ کے کہنے پر ہم
کسی آیت کو منسوخ قرار نہیں دے سکتے.ایک آیت کے قرآن کریم کا حصہ ہونے پر جس قسم کی شہادت مہیا ہے
اسی قسم کی شہادت اگر اس کے منسوخ ہونے پر ہو تو ہی قابل توجہ ہو سکتی ہے.مگر یہ حقیقت بھی ظاہر وباہر ہے کہ تمام
صحابہ کسی آیت کے منسوخ ہونے پر متفق نہیں.بلکہ کسی آیت کے منسوخ ہونے پر صحابہ کی کوئی چھوٹی سی جماعت
بھی متفق نظر نہیں آتی جو پانچ یا چھ افراد پر ہی مشتمل ہو.پس اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ اُن کی ذاتی رائے تھی اور
اس رائے کا مطلب وہی تھا جو امام الزماں علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ اپنے معنی کو منسوخ قرار دیتے تھے
آیت کو نہیں.جہاں تک اُن آیات کا تعلق ہے جن کے بارہ میں کہا جاتا ہے کہ قرآن کریم سے منسوخ کر دی گئی ہیں مگر
الفاظ پیش نہیں کرتے اس لیے ایساد عومی قابل اعتبار نہیں رہتا.پھر قائلین نسخ کے نزدیک کچھ ایسی آیات ہیں کہ جن کے معنی تو قائم ہیں مگر الفاظ منسوخ ہیں.یہ تو بات ہی
بے وقوفی والی ہے.الفاظ منسوخ کرنے کی کیا تک اور حکمت ہے.یہ بے حکمت اور فضول کام خدا کی طرف
منسوب
نہیں کی جاسکتا.
Page 408
الذكر المحفوظ
392
اسی طرح قائلین نسخ ایک آیت پیش کرتے ہیں جس میں ایک واقعہ کا ذکر ہے کہ یہ بھی منسوخ ہوگئی ہے.یہ
بات بھی عجیب ہے.حکم کے منسوخ ہونے کی کچھ سمجھ بھی آتی ہے کہ جو لوگ خدا تعالیٰ کی صفت قدوس کو عملی طور پر
نہیں مانتے اور یہ تسلیم نہیں کرتے کہ خدا تعالیٰ ہر قسم کی غلطی سے پاک ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک حکم
دیا اور پھر علم ہوا کہ اس حکم سے بہتر حکم دیا جا سکتا ہے تو اُس نے گزشتہ حکم منسوخ کر دیا اور نیا حکم نازل کر دیا لیکن
واقعہ جو ہو چکا ہے وہ تو منسوخ نہیں ہوسکتا.وہ تو معرض وجود میں آچکا اور ماضی کا حصہ بن چکا.پھر اس کے
منسوخ کرنے سے کیا مراد؟ کیا تاریخ جو وقوع پذیر ہو چکی منسوخ ہوسکتی ہے.مثلا کسی قائل نسخ کے ساتھ یہ واقع
ہو جائے کہ اس کا کوئی عزیز فوت ہو جائے اور وہ اپنے ہاتھوں سے اس کی میت کو غسل دے اور تجہیز و تکفین
کرے.اب وہ کس طرح اس واقعہ کو منسوخ کرے گا ؟ کیا وہ یہ اعلان کرے گا کہ یہ واقع ہوا تھا اب اسے منسوخ
سمجھیں اور ماضی کا حصہ نہ سمجھیں؟ واقعہ کے منسوخ کرنے سے تو صرف یہی مراد ہو سکی ہے کہ جو واقعہ بیان کیا گیا
ہے وہ درست نہیں تھا.غلطی ہو گئی اس لیے وہ حذف کر دیا جائے.مگر کیا خدا تعالیٰ سے ایسی غلطی کی امید رکھی
جاسکتی ہے.مفسرین کا بھی اس پر اجماع ہے کہ واقعہ منسوخ نہیں ہوسکتا.قائلین نسخ کی طرف سے ایک من گھڑت اور عجیب و غریب واقعہ پیش کیا جاتا ہے کہ دو افراد تھے جن میں سے
ایک نے ایک آیت پڑھنے کی کوشش کی تو اسے یاد نہ آئی.اس نے دوسرے سے پوچھی تو اسے بھی بھول چکی تھی.وہ
باہر نکلے اور دوسرے صحابہ سے پوچھنے لگے مگر سب صحابہ کو بھول چکی تھی اور کوئی بھی اُس آیت کے الفاظ نہ بتا سکا.یہ واقعہ کب ہوا؟ اُن دو افراد کے نام کیا تھے؟ وہ کس قبیلہ یا خاندان سے تعلق رکھتے تھے؟ وہ کیا کرتے تھے
کہاں رہتے تھے؟ کسی قسم کی کوئی مستند تفصیل کتب تاریخ میں نہیں ملتی.اس واقعہ کے راوی کون ہیں؟ کچھ علم نہیں !
بس درج کر دیا گیا کہ یہ واقعہ ہوا تھا کبھی.آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں سینکڑوں حفاظ تھے مگر روایت میں دو
ایسے صحابہ کا ذکر ملتا ہے جن کو کوئی نہیں جانتا اور ان کے آباء کا بھی علم نہیں.روایت کے کچھ اصول ہیں ان پر بھی یہ
روایت پوری نہیں اترتی کیوں کہ راوی بھی مذکور نہیں کہ کون ہیں.پھر بھولنے والی بات تو عقل کو کسی طرح تسلیم نہیں
کیونکہ اس صورت میں شور پڑ جانا چاہیے تھا.پس یہ روایت درایت کے اصولوں پر پوری نہیں اترتی.یہ بات بھی قابل غور ہے کہ ننسها کے معنی قرآن کے بھولنے کے کیسے لیے جاسکتے ہیں جبکہ قرآن خود فرماتا
ہے کہ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسی چنانچہ جب قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود خدا نے لیا ہے جو پھر اس کے بھولنے یا
منسوخ ہونے کے کیا معنے؟ اللہ خود فرماتا ہے؛ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحفِظُون پھر اگر بھلایا یا
منسوخ کیا جاسکتا ہے تو پھر حفاظت کے کیا معنی؟
سوال یہ ہے کہ جب یہ مسئلہ اتنا ہے بعید از عقل ہے تو پھر کیوں امت مسلمہ میں اسقدر رائج ہو گیا؟ اس کا
Page 409
قرآن کریم کی معنوی محافظت
393
جواب یہ ہے کہ اس کی وجہ کورانہ تقلید بنی ہے.ابتدا میں جب سخ کا لفظ استعمال کیا گیا تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا جو
آج معروف ہو چکا ہے.ابتدا میں نسخ سے مراد صرف یہ تھی کہ قرآن کریم کی ایک آیت کے جو معنی ہم سمجھتے تھے
قرآن کریم کی ایک نئی نازل ہونے والی آیت نے یفسر بعضه بعضا کے مطابق اس کے وہ معانی کھول دیے
ہیں جو حقیقی ہیں اور جو ہم سمجھتے تھے وہ معنی رد کر دیے ہیں.پس وہ معنے منسوخ ہو گئے ہیں اور بہتر معانی عطا ہوئے
ہیں.یہی حقیقت مضمون کی ابتدا میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الفاظ میں درج کی جاچکی ہے.بعد میں آنے والوں نے اندھی تقلید کرتے ہوئے مسئلہ تو اپنا لیا مگر اس کے صحیح مفہوم کو اپنا نہ سکے.واللہ اعلم.بہر حال حقیقت جو بھی ہو یہ واضح ہے کہ اگر اس سارے مسئلہ کا تجزیہ کیا جائے تو عقل اسے دھکے دیتی ہے.تاریخ
بھی کوئی سہارا نہیں دیتی.اگر کوئی دلیل بن سکتی ہے منسوخ شدہ آیت کی تو یہ ہی بن سکتی ہے اور ہمیشہ مختلف الفاظ
کے جامے میں لپیٹ کر یہی بنائی گئی ہے کہ فلاں آیت چونکہ سمجھ میں نہیں آتی اس لیے منسوخ ہے.یا فلاں آیت
باقی قرآنی آیات کے متضاد معلوم ہوتی ہے اس لیے منسوخ ہے.پس سمجھ نہیں آتی تو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے
اور اگر متضاد معلوم ہوتی ہے تو یہ بھی فہم قرآن کی کمی ہے کیوں کہ قرآن
کریم کا تو یہ دعویٰ ہے کہ قرآن کریم میں کچھ
اختلاف نہیں ہے.اللہ فرماتا ہے کہ اگر اختلاف ہوا تو سمجھ لو کہ قرآن خدا کی طرف سے نہیں.یہ تو کہیں نہیں فرمایا
کہ اگر اختلاف ہو تو ایک آیت کو منسوخ قرار دے لو.یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ عدم علم سے عدم سے لازم نہیں“
اور اسی حقیقت کے برعکس پر ناسخ اور منسوخ کے مسئلہ کی بنیاد ہے.یعنی اس مسئلہ کی بنیاد کسی حقیقت پر نہیں بلکہ
عدم علم اور کم نہی پر ہے اور یہ وہ واحد مسئلہ ہے کہ جس کی بنیاد بر ملاطور پر نا بھی اور جہالت پر رکھی گئی ہے اور باقائدہ
اقرار کیا جاتا ہے کہ فلاں آیت چونکہ سمجھ نہیں آئی اس لیے منسوخ ہے.الفاظ جو بھی ہوں مفہوم یہی ہوتا ہے.اس
لحاظ سے دیکھا جائے تو امام الزماں حکم و عدل علیہ السلام کے کے اس فیصلہ کے بعد عقیدہ نسخ فی القرآن کا سب
سے بڑا علمبر دار وہی ہو گا جسے سب سے کم آیات کا فہم نصیب ہوگا اور قرآن مجید کی تفسیر سے سب سے زیادہ
ناواقف اور قرآنی تعلیمات کے عرفان سے سب سے زیادہ دور ہوگا.
Page 410
الذكر المحفوظ
394
قرآن کریم کی دائمی حفاظت کا وعدہ ہے
ابن و راق اور اس قماش کے باقی لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی بشارت ہے جو یقیناً اس کے ہوش اُڑا دے
گی اور یہ نوید سنادے گی کہ جو انجام گزشتہ ادوار میں قرآن کریم کے بارہ میں شک پیدا کرنے والوں کا ہوا وہی
تمہار بھی ہے.ناکامی، نامرادی اور ذلت وہ خوشخبری یہ کہ آئندہ زمانہ میں بھی قرآن کریم کی حفاظت پر کوئی
آنچ آئے اس بات کا دُور دُور تک کوئی امکان نہیں.جو کتاب اب اتنی کثرت سے شائع ہوتی ہے، سب سے
زیادہ پڑھی جاتی ہے ، لاکھوں حفاظ موجود ہیں، ساری دُنیا میں تلاوت کرنے والے موجود ہیں ، وہ کس طرح بدلی
جاسکتی ہے؟ ناممکن ہے.یہ تو عام دنیاوی حالات دیکھ کر ایک تسلی ملتی ہے.اس کے علاوہ ایک اور بشارت بھی ہے
ابن وراق کے لیے.قرآن کریم کی حفاظت کرنے والا سب سے بڑھ کر قادر اور توانا خدا اس کی حفاظت پر نگران
ہے.کیسے ممکن ہے کہ نادانستہ بشری کو تا ہی یا دانستہ بشری کوشش اس میں کوئی کمی یا بیشی یا کوئی تغیر یا تبدل کر سکے.یہ کلیہ ناممکن ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کی معنوی حفاظت کا بھی ایک بے نظیر انتظام یہ فرمایا کہ امت محمدیہ
سے یہ عہد کیا کہ ہر دور میں اور ہر زمانہ میں اللہ تعالیٰ اپنی جناب سے ایسے کامل افراد کو پیدا کرتارہے گا جو خدا تعالیٰ
سے براہ راست را ہنمائی پا کر قرآن کریم کی صحیح تعلیم کی اشاعت کرتے رہیں گے.حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں:
” ہم نے ہی اس کتاب کو اتارا اور ہم ہی اس تنزیل کی محافظت کریں گے.اس میں اس بات
کی تصریح ہے کہ یہ کلام ہمیشہ زندہ رہے گا اور اس کی تعلیم کو تازہ رکھنے والے اور اس کا نفع لوگوں کو
پہنچانے والے ہمیشہ پیدا ہوتے رہیں گے.“ (شہادت القرآن روحانی خزائن جلد 6 صفحہ 338)
اس جگہ یہ بھی واضح رہے کہ اللہ جل شانہ، قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا
الذِّكْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحفِظُون یعنی ہم نے ہی اس کتاب کو اتارا اور ہم ہی اس تنزیل کی محافظت
کریں گے اس میں اس بات کی تصریح ہے کہ یہ کلام ہمیشہ زندہ رہے گا اور اس کی تعلیم کو تازہ
رکھنے والے اور اس کا نفع لوگوں کو پہنچانے والے ہمیشہ پیدا ہوتے رہیں گے اور اگر یہ سوال ہو
کہ قرآن کے وجود کا فائدہ کیا ہے جس فائدہ کے وجود پر اس کی حقیقی حفاظت موقوف ہے تو اس
دوسری آیت سے ظاہر ہے هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّنَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا
عَلَيْهِمْ آيَتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَبَ وَالْحِكْمَةَ - [الجمعة: 3] اس آیت کا
خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کے بڑے فائدے دو ہیں جن کے پہنچانے کے لیے آنحضرت صلی اللہ
Page 411
قرآن کریم کی معنوی محافظت
395
علیہ والہ وسلم تشریف لائے تھے.ایک حکمت فرقان یعنی معارف و دقائق قرآن.دوسری تاثیر قرآن جو موجب تزکیہ نفوس
ہے اور قرآن کی حفاظت صرف اسی قدر نہیں جو اس کے صحفت مکتو بہ کو خوب نگہبانی سے رکھیں
کیونکہ ایسے کام تو اوائل حال میں یہود اور نصاری نے بھی کیے یہاں تک کہ توریت کے نقطے بھی
گن رکھے تھے.بلکہ اس جگہ مع حفاظت ظاہری حفاظت فوائد و تا ثیرات قرآنی مراد ہے اور وہ
موافق سنت اللہ کے تبھی ہو سکتی ہے کہ جب وقتاً فوقتاً نائب رسول آویں جن میں ظلی طور پر
رسالت کی تمام نعمتیں موجود ہوں اور جن کو وہ تمام برکات دی گئی ہوں جو نبیوں کو دیجاتی ہوں
جیسا کہ ان آیات میں اسی امر عظیم کی طرف اشارہ ہے اور وہ یہ ہے وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا
مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ
قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَةِ لَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا
يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ
پس یہ آیت در حقیقت اس دوسری آیت إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ
النور : ۵۶ کے لیے بطور تفسیر کے واقعہ ہے اور اس سوال کا جواب دے رہی ہے کہ حفاظت قرآن
کیونکر اور کس طور سے ہوگی.سو خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس نبی کریم کے خلیفے وقتاً فوقتاً بھیجتا
رہوں گا اور خلیفہ کے لفظ کو اشارہ کے لیے اختیار کیا گیا کہ وہ نبی کے جانشین ہوں گے اور اس کی
برکتوں میں سے حصہ پائیں گے جیسا کہ پہلے زمانوں میں ہوتا رہا اور ان کے ہاتھ سے برجائی
دین کی ہوگی اور خوف کے بعد امن پیدا ہوگا یعنی ایسے وقتوں میں آئیں گے کہ جب اسلام تفرقہ
میں پڑا ہوگا.پھر ان کے آنے کے بعد جو ان سے سرکش رہے گا وہی لوگ بد کار اور فاسق ہیں.یہ
اس بات کا جواب ہے کہ بعض جاہل کہا کرتے ہیں کہ کیا ہم پر اولیاء کا ماننا فرض ہے.سواللہ تعالیٰ
فرماتا ہے کہ بیشک فرض ہے اور ان سے مخالفت کرنے والے فاسق ہیں اگر مخالفت پر ہی مریں.شہادۃ القرآن روحانی خزائن جلد ششم صفحه 339 338 )
پھر فرماتے ہیں:
یہ آیت کہ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَوَ إِنَّا لَهُ لَحفِظُون بجز اس کے اور کیا معنی رکھتی ہے
که قرآن سینوں سے محو نہیں کیا جائے گا جس طرح کہ توریت اور انجیل یہود اور نصاریٰ کے
سینوں سے محو کی گئی اور گو توریت اور انجیل ان کے ہاتھوں اور ان کے صندوقوں میں تھی لیکن ان
کے دلوں سے محو ہو گئی یعنی ان کے دل اس پر قائم نہ رہے اور انہوں نے توریت اور انجیل کو اپنے
Page 412
الذكر المحفوظ
396
دلوں میں قائم اور بحال نہ کیا.غرض یہ آیت بلند آواز سے پکار رہی ہے کہ کوئی حصہ تعلیم قرآن کا
بر باد اور ضائع نہیں ہوگا اور جس طرح روز اول سے اس کا پودا دلوں میں جمایا گیا.یہی سلسلہ
قیامت تک جاری رہے گا.“
شہادت القرآن روحانی خزائن جلد 6 صفحہ 351)
ي حديث (إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِئَةٍ سَنَةٍ مَنْ
يُجَدِّدُ لَهَا دِيْنَهَا - ناقل) إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِكْرَوَ إِنَّا لَهُ لَحَفِظُون کی شرح ہے.صدی
ایک عام آدمی کی عمر ہوتی ہے اس لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ
سوسال بعد کوئی نہ رہے گا.جیسے صدی جسم کو مارتی ہے اسی طرح ایک روحانی موت بھی واقع
ہوتی ہے.اس لیے صدی کے بعد ایک نئی ذریت پیدا ہو جاتی ہے.جیسے اناج کے کھیت.اب
دیکھتے ہیں کہ ہرے بھرے ہیں ایک وقت میں بالکل خشک ہوں گے پھر نئے سر سے پیدا ہو
جائیں گے اس طرح پر ایک سلسلہ جاری رہتا ہے.پہلے اکا برسوسال کے اندر فوت ہو جاتے
ہیں اس لیے خدا تعالیٰ ہر صدی پر نیا انتظام کر دیتا ہے جیسا رزق کا سامان کرتا ہے.پس قرآن
کی حمایت کے ساتھ یہ حدیث تواتر کا حکم رکھتی ہے.قرآن شریف کی تعلیم کا محرف مبدل ہونا اس لیے محال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے.إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِكرَ وَإِنَّا لَهُ لَحفِظُون.(سورة الحجر الحجز ونمبر ۱۴) یعنی اس کتاب کو ہم نے
ہی نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ رہیں گے.سو تیرہ سو برس سے اس پیشینگوئی کی
صداقت ثابت ہو رہی ہے.اب تک قرآن شریف میں پہلی کتابوں کی طرح کوئی مشر کا نہ تعلیم
ملنے نہیں پائی اور آئندہ بھی عقل تجویز نہیں کر سکتی کہ اس میں کسی نوع کی مشر کا نہ تعلیم مخلوط
ہو سکے.کیونکہ لاکھوں مسلمان اس کے حافظ ہیں.ہزار ہا اس کی تفسیریں ہیں.پانچ وقت اس
کی آیات نمازوں میں پڑھی جاتی ہیں.ہر روز اس کی تلاوت کی جاتی ہے.اسی طرح تمام
ملکوں میں اس کا پھیل جانا.کروڑ ہا نسخے اس کے دنیا میں موجود ہونا.ہر یک قوم کا اس کی تعلیم
سے مطلع ہو جانا.یہ سب امور ایسے ہیں کہ جن کے لحاظ سے عقل اس بات پر قطع واجب کرتی
ہے کہ آئندہ بھی کسی نوع کا تغیر اور تبدل قرآن شریف میں واقع ہونا تمنع اور محال ہے.“
(براہین احمد یہ روحانی خزائن جلد اول صہ 102 حاشیہ نمبر 9 ایڈیشن اول صہ 111 )
اسی طرح فرماتے ہیں:
پھر بعض اور آیات ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ ضرور خداوند کریم نے یہی ارادہ فرمایا ہے
که روحانی معلم جو انبیاء کے وارث ہیں ہمیشہ ہوتے رہیں اور وہ یہ ہیں.وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ
Page 413
397
قرآن کریم کی معنوی محافظت
آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ
مِنْ قَبْلِهِمْ.وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبَهُمُ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْتَحُلُّ قَرِيباً مِّنْ
دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللهِ.إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَاد الجز و نمبر ١٣ وَمَا كُنَّا
مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا یعنی خدا تعالیٰ نے تمہارے لیے اے مومنان امت محمد یہ ہے
وعدہ کیا ہے کہ تمہیں بھی وہ زمین میں خلیفہ کرے گا جیسا کہ تم سے پہلوں کو کیا اور ہمیشہ کفار پر کسی
قسم کی کوفتیں جسمانی ہوں یا روحانی پڑتی رہیں گی یا ان کے گھر سے نزدیک آجائیں گی.یہاں
تک کہ خدا تعالیٰ کا وعدہ آپہنچے گا اور خدا تعالیٰ اپنے وعدوں میں میں تخلف نہیں کرتا اور ہم کسی
قوم پر عذاب نازل نہیں کرتے جب تک ایک رسول بھیج نہ لیں.ان آیات کو اگر کوئی شخص تامل اور غور کی نظر سے دیکھے تو میں کیونکر کہوں کہ وہ اس بات کو سمجھ
نہ جائے کہ خدا تعالیٰ اس امت کے لیے خلافت دائی کا صاف وعدہ فرماتا ہے.اگر خلافت
دائی نہیں تھی تو شریعت موسوی کے خلیفوں سے تشبیہ دینا کیا معنی رکھتا تھے اور اگر خلافت راشدہ
صرف تیں برس تک رہ کر پھر ہمیشہ کے لیے اس کا دور ختم ہو گیا تھا اس سے لازم آتا ہے کہ خدا
تعالیٰ کا ہرگز یہ ارادہ نہ تھا کہ اس امت پر ہمیشہ کے لیے ابواب سعادت مفتوح رکھے کیونکر
روحانی سلسلہ کی موت سے دین کی موت لازم آتی ہے اور ایسا مذہب ہرگز زندہ نہیں کہلا سکتا
جس کے قبول کرنے والے خود اپنی زبان سے ہی یہ اقرار کریں کہ تیرہ سو برس سے یہ مذہب مرا
ہوا ہے اور خدا تعالیٰ نے اس مذہب کے لیے ہر گز یہ ارادہ نہیں کیا کہ حقیقی زندگی کا وہ نور جو نبی کریم
کے سینہ میں تھا وہ توارث کے طور پر دوسروں میں چلا آوے.(شهادة القرآن روحانی خزائن جلد شم صفحه 34 تا 35)
حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب خلیفتہ مسیح الثانی المصلح الموعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:
اب رہا آئندہ کا سوال سو اس کا اول تو یہ جواب ہے کہ اس وقت تک اس میں کوئی تغیر نہیں
ہوا اور آئندہ کے لیے قرآن کریم میں پیشگوئیاں موجود ہیں کہ جب بھی مسلمان اسلام سے
غافل ہوں گے اللہ تعالیٰ ان میں مامور بھیجتا رہے گا.پس اس وعدہ کی موجودگی میں ہم یقین
رکھتے ہیں کہ چونکہ قرآن کریم سے ہمیشہ دنیا کی ضرورت پوری ہوتی رہے گی...یقیناوہ ہمیشہ
اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہے گا کیونکہ کوئی عقلمند آدمی اپنی کارآمد شے کو تباہ نہیں ہونے دیتا اور
اللہ تعالیٰ تو سب عقلمندوں سے بڑھ کر عقلمند ہے.“
( تفسیر کبیر جلد چہارم صفحه 22 زیر تفسیر آیت الحجر 10)
Page 414
الذكر المحفوظ
398
قرآن کریم کے بعد اور کسی الہامی کتاب کے نزول کی ضرورت نہیں
یہاں ایک خیال دل میں پیدا ہوتا ہے کہ زمانہ بہت تیزی سے بدل رہا ہے.کیسے ممکن ہے کہ ان بدلتے حالات
میں تعلیم وہی کام آئے جو پندرہ سو سال پہلے نازل کی گئی.یقینا بدلتے حالات اور جدید تقاضوں کے مطابق نئی تعلیم کی
ضرورت بھی پڑتی ہے.پس قرآن کریم بے شک محفوظ رہے لیکن نئی تعلیم کی ضرورت بہر حال موجود ہے.اس ضمن میں مختصر اعرض ہے کہ یہ ذکر گزرچکا ہے کہ قرآن کریم کا یہ دعوی ہے کہ یہ ایک کامل کتاب ہے جس
میں قیامت تک بنی نوع کی تمام ضروریات اور مسائل کا حل موجود ہے.ہاں یہ تمام مضامین ضرورت حقہ کے
مطابق ظاہر ہوں گے.یعنی جوں جوں زمانہ اپنی ضروریات اور مسائل پیش کرے گا قرآن کریم ان ضروریات کو
پورا کرے گا اور ان مسائل کا حل پیش فرماتا چلا جائے گا.چنانچہ آج بھی ضرورتِ زمانہ کے مطابق قرآن کریم
کے معارف ظاہر ہورہے ہیں اور آئندہ بھی ہوتے چلے جائیں گے.حضرت
مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں:
قرآن شریف ایسے زمانہ میں آیا تھا کہ جس میں ہر ایک طرح کی ضرورتیں کہ جن کا پیش آنا
ممکن ہے پیش آگئی تھیں.یعنی تمام امور اخلاقی اور اعتقادی اور قولی اور فعلی بگڑ گئے تھے اور ہر
ایک قسم کا افراط تفریط اور ہر یک نوع کا فسادا اپنے انتہاء کو پہنچ گیا تھا.اس لیے قرآن شریف کی
تعلیم بھی انتہائی درجہ پر نازل ہوئی.پس انہی معنوں سے شریعت
فرقانی مختتم اور مکمل ٹھہری اور
پہلی شریعتیں ناقص رہیں کیونکہ پہلے زمانوں میں وہ مفاسد کو کہ جن کی اصلاح کے لیے الہامی
کتابیں آئیں وہ بھی انتہائی درجہ پر نہیں پہنچے تھے اور قرآن شریف کے وقت میں وہ سب اپنی
انتہاء کو پہنچ گئے تھے.پس اب قرآن شریف اور دوسری الہامی کتابوں میں فرق یہ ہے کہ پہلی
کتابیں اگر ہر یک طرح کے خلل سے محفوظ بھی رہتیں پھر بھی بوجہ ناقص ہونے تعلیم کے ضرور تھا
کہ کسی وقت کامل تعلیم یعنی فرقان مجید ظہور پذیر ہوتا.مگر قرآن شریف کے لیے اب یہ ضرورت
در پیش نہیں کہ اس کے بعد کوئی اور کتاب بھی آوے.کیونکہ کمال کے بعد اور کوئی درجہ باقی نہیں
ہاں اگر یہ فرض کیا جائے کہ کسی وقت اصول حقہ قرآن شریف کے وید اور انجیل کی طرح مشرکانہ
اصول بنائے جائیں گے اور تعلیم توحید میں تبدل اور تحریف عمل میں آوے گی اور اگر ساتھ اس
کے یہ بھی فرض کیا جائے جو کسی زمانہ میں وہ کروڑہا مسلمان جو تو حید پر قائم ہیں وہ بھی پھر طریق
شرک اور مخلوق پرستی کا اختیار کر لیں گے تو بے شک ایسی صورتوں میں دوسری شریعت اور
دوسرے رسول کا آنا ضروری ہوگا.مگر دونوں قسم کے فرض محال ہیں.“
( براہین احمدیہ ہر چہار حصص ، روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 101 حاشیہ )
Page 415
اشاریہ
399
انڈیکس
انڈیکس آیات قرآن کریم
انڈیکس اعتراضات
انڈیکس اسماء
Page 417
الذكر المحفوظ
بسم
الله الرحمن الرحـ
الفاتحه
i
انڈیکس آیات قرآن کریم
حافظوا على الصلوات...(239)
[180] [179] [17][3] لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ (257)
اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ (2)
[43] [244] [256] [273] [274] [303]
[270]
[378]
أمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ...(286) [153]
آل عمران
لعنة الله على الكاذبين- [62]
[235] [268]
ولقد صدقكم اللـ ــه وعــده اذ
تحسونهم....153 تا 155)
النساء
وجئنابك على هَؤُلَاءِ شهيدًا ( 42 )
لَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ....(83)
[363]
[42]
[125] [378] [383] [388]
[19]
لا يستوى القاعدون....(96,97)
المائده
الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ....نِعْمَتِي (4)
[234]
يا أيها الرسول بلغ....مِنَ النَّاسِ(68)
[157] [168] [258] [315]
[255]
[255]
[369]
[243]
[225]
[243]
[43] [244] [246] [30]
[244]
الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (3)
ملِكِ يَوْمِ الدِّين (4)
اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (6)
[278] [374]
صِرَاطَ الَّذِينَ....وَلَا الضَّالِين (7)
[273] [277] [279] [374] [366]
[41][236] [248]
البقرة
الم (2)
ذلك الكتاب...هدى للمتقين (3)
[45] [209] [236] [248]
[236]
يَايُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا....تَتَّقُونَ (22)
لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ (83)
وَإِنْ كُنْتُمْ فِي....لِلْكَفِرِيْنَ (2524) وَإِذَا سَمِعُوا (84)
لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ (44)
قولوا للناس حسنا (84)
[18P
[202]
[214]
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا...اهْتَدَيْتُمْ (106)
الانعام
ما فرطنا في الكتاب من شيءٍ [39]
مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ...قَدِيرٌ - (107)
الَّذِينَ آتَيْنَهُمُ الْكِتَبَ.....(122)
[385] انْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الآيت...(47)
[44]
ان الله يحب المحسنين (196) [214] | لَا وَّلَا ا رَطْبٍ وَّ لَا يَابِس....مُّبِيْنٍ (60)
لیس علیکم جناح ان تبتغوا (199)
[214] [270]
Page 418
الذكر المحفوظ
وما انا عليكم بحفيظ (105)
[311] [319]
وَ كَذلِكَ لَنُصَرِفُ الْآيَتِ....(106)
ii
فَإِلْمْ يَسْتَجِيْبُوْالَكُمْ....بِعِلْمِ اللهِ (15)
[229]
قل ان صلوتی و نسکی.....(163)
الاعراف
ولله الاسماء الحسنى.....(181)
وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا...(205)
الانفال
وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ.....(18)
وَاذْكُرُوا اللهَ كَثِيرًا.....( 46 )
التوبة
[237]
[153]
[214]
يوسف
لا تثريب عليكم اليوم (93)
الرعد
[154]
و اما ما ينفع الناس.....الارض (18) [374]
ولا يزال الذين كفروا...الميعاد (32)
الحجر
[375] [397]
[40] تلك آيت الْكِتَبِ وَ قُرْآنٍ مُّبِينٍ (2)
[320]
ربما يود الذين(3)
وَقَالُوْايَأَيُّهَا
[255] [386]
[255]
وَقَالُوا يَأَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ....لَمَجْنُونٌ (3) [3]
[254] [253] | إنا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ....(10)
يُرِيْدُوْنَ أَنْ يُطْفِوُا.....الْكَفِرُوْنَ (32) [362]
لا تحزن ان الله معنا(41)
يونس
[154]
[vii,viii] [4] [5] [7][27] [35] [65] [73][173]
[339] [350] [351] [370] [371] [373] [374]
[376] [381] [392] [394][395] [396]
وَ إِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا..مَّعْلُوْمٍ (22)..النحل
قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَاءَ نَا....(16) فَاسْتَلُوا أَهْلَ الذِّكْر...تَعْلَمُوْنَ (44)
[123] [124] [181] [183]
قُلْ لَّوْ شَاءَ اللهُ مَا تَلَوْتُ.....(17)
[135] [126] وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ....شَيْءٍ (90)
مَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُم إِلَّا ظَنَّا...شَيْئًا (37) فَإِذَا قَرَأْتَ القُرآنَ فَاسْتَعِذْ.....(99)
[120]
[243]
[337]
[243]
وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَ مَا تَتْلُوا....(62)
[63]
بنی اسرائیل
[39]
هود
الركِتب أُحْكِمَتْ ايتُهُ ثُمَّ....(2) [238]
أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللهُ إِنَّنِي لَكُمْ مِنْهُ...(3)
[236] [238]
و أَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمُ....كَبِيرٍ (4) [238]
وقل لعبادى يقولوا التي هي احسن (8)
[214]
وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا (16)
[375] [397]
[40]
أَقِمِ الصَّلوةَ لِدَلُوكِ....مَشْهُودًا (79)
Page 419
الذكر المحفوظ
بالْحَقِّ أَنْزَلْنَهُ وَ بِالْحَقِّ نَزَلَ (106)
النمل
[124] قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ...يَفْعَلُونَ (35)
العنكبوت
بل هوايات بينات...العلم (50)
و قُرْآنًا فَرِقْنَهُ لِتَقْرَأَهُ....تَنْزِيلًا (107) [12]
الكهف
[148]
[373]
قُلْ لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ....مَدَدًا - (110) [242] وَقَالُوْا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ...مُّبِينٌ (51) [125]
طه
والذين جاهدوا فينا....سبلنا (70) [375]
الله لا اله الاهو له الاسماء الحسنى (9) السجده
[214] | الم تنزيل (23)
تَنْزِيل(2,3)
[68]
انه من يات ربه...يحي (75) [371] الذي أحسن كل شيء خلقه (32) [214]
فَتَعلَى اللهُ الْمَلِكُ...عِلْمًا - (115)
الحج
[62] [66]
الاحزاب
منهم من قضى...ينتظر (24)
[163]
احلت لكم..الانعام عليكم (31) [184]
وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ...أُمُنِيَّتِهِ ))
وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ....حَكِيمٌ (53)
المؤمنون
[106]
[62] [106]
ملعونين - اينما ثقفوا...تقتيلاً [62] [265]
الزمر
اللهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيْثِ...هَادٍ - (24)
المؤمن
[16] [213] [240] [245]
و صوركم فاحسن صوركم (40) [214]
وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ....طِيْن (13) [117] السجده
ثُمَّ أَنشَأْ نَهُ خَلْقاً آخَرَ...الْخَالِقِيْنَ (15) إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا...حَمِيْدٍ (43،42)
النور
[110] [111] [11] [215]
وعد الله الذين امنوا....لفاسقون (56)
الفرقان
[375] [395] [397]
وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ...وأَصِيلًا (6)
الشورى
[16]
فَمَا أُوتِيتُم مِّن....يُنفِقُونَ (37 تا 39) [334]
الاحقاف
وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ أَيْتُنَا..سِحْرٌ مُّبِينٌ (8)
[69] [15] | الفتح
وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ...تَرْتِيْلاً (33) تؤزروه و توقروه (10)
الشعراء
[220]
[141]
[208] [181] [13] إِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُونَكَ....أَيْدِيهِمْ (11) [320]
ق
انذر عشيرتك الاقربين (132) [131] ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ (1)
[51]
Page 420
الذكر المحفوظ
الذريت
iv
القيمة
وَ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ...لِيَعْبُدُون (57) [236] إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَ قُرْآنَهُ (18)
النجم
وَمَا يَنْطِقُ عَن....فَاسْتَوَى (4 تا 7)
ولقد راه نزلة اخرى (14)
النبا
[192] [160] [61] عَمَّ يَتَسَاءَ لُوْنَ (2)
[108]
لقد رأى من آيات ربه الكبرى (19) [108]
افرئيتم اللات والعزى (20)
[109]
التكوير
[3][65][17][181] [205]
وَإِذَا الشَّمْسُ كُوّرَت (2)
الاعلى
[109] سنقرئك فلا تنسي (7)
ان هي الا اسماء سميتموها...(24) [109]
فاسجدوا لله واعبدوا (63)
[156]
[156]
القمر
وَ لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْر (23)
الرحمن
[253]
الا ماشاء الله(8)
العلق
[63] [64] [65] [340] [392]
[63] 64[65] [336] [340]
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِ بْنِ - (14) اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَق(2)
الواقعه
[252] [253][254]
الكافرون
لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُوْن (80) [371] [39] قُلْ يَأْيُّهَا الْكَافِرُونَ (2)
الصف
لِمَ تَقُولُونَ مَالًا....تَفْعَلُونَ (443) [369]
الجمعة
هُوَ الَّذِي بَعَثَ....وَالْحِكْمَةَ (3)
[16] [50] [67] [371] [380] [394]
لهب
تُبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ (2)
الاخلاص
قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (2)
[15] [208]
[315] [316]
[277]
[186] [187] [277] [312]
وَاخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْابِهِمْ (4) [277] | اللهُ الصَّمَدُ كُفُوًا أَحَد (3 تا 5) [279]
الحاقة
الفلق....انه لقول رسول كريم....حاجزين (41 تا 48) قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (2)
[218]
[183][186] [276] [277] [278] [312]
الملک
تَبَارَكَ الَّذِي بَيَدِهِ الْمُلْكَ (2)
[68]
الناس
قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ(2)
[186] [187] [276] [278] [312]
Page 421
الذكر المحفوظ
انڈیکس اعتراضات
اس وسوسہ کا جواب کہ قرآن کریم رسول کریم 12 اس وسوسہ کا جواب کہ شیطانی آیات کا قصہ
کے زمانہ میں محفوظ نہیں کیا گیا تھا بلکہ آپ کے ظاہر کرتا ہے کہ رسول کریم نے قرآن کریم
وصال کے بعد میں ادھر اُدھر سے جو حصہ وحی
میں رد و بدل کیا تھا.13 اس وسوسہ کا جواب کہ رسول کریم لوگوں کی
ملا اُسے اکٹھا کر لیا گیا.2 اعتراض که مسلمان قرآن کو بے معنی پڑھتے ہیں 35 مرضی سے قرآن کریم کی آیات میں تبدیلی
اس وسوسہ کا جواب کہ ہوسکتا ہے کہ رسول کریم کر لیا کرتے تھے.57
اعتراض کہ ایسا کیونکر ممکن ہے کہ جو آیت نبی
63 16 اس وسوسہ کا جواب کہ رسول کریم کو لوگ اس
70
آپ نبوت کا دعویٰ کر دیں گے.105
110
119
132
کچھ آیات بھول گئے ہوں.4 اس وسوسہ کا جواب کہ اسلامی تاریخ میں اہم کریم پر نازل ہو وہی دوسروں کو بھی وحی ہو.115
معاملات میں شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں 57 15 اس وسوسہ کا جواب کہ ہوسکتا ہے رسول کریم
اس وسوسہ کا جواب کہ قرآن کریم کے مطالعہ نے اپنی طرف سے قرآن کریم میں کوئی
سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ رسول کریم ضرور کچھ تبدیلی کی ہو.آیات قرآنیہ بھول گئے ہونگے.اس وسوسہ کا جواب کہ ہوسکتا ہے صحابہ سے کچھ لیے سچا کہہ دیتے تھے کہ انہیں یہ علم نہ تھا کہ
آیات قرآنیہ ضائع ہوگئی ہوں.اس وسوسہ کا جواب کہ ہوسکتا ہے کہ کاتبین وحی نے 17 اس وسوسہ کا جواب کہ رسول کریم نے دنیاوی
غلطی سے کچھ آیات قرآنیہ غلط لکھ دی ہوں.منفعت کے لیے یہ سلسلہ شروع کیا.اس اعتراض کا جواب کہ رسول کریم نے قرآن 18 اس وسوسہ کا جواب کہ رسول کریم اپنی فطرتی
کریم ایک کتاب کی شکل میں پیش نہیں کیا.78 رحم دلی کی وجہ سے بنی نوع کی نا گفتہ بہ حالت
و حضرت ابوبکر نے آسان راہوں کو چھوڑ کر جمع کے علاج کے طور پر یہ تعلیم بنائی تھی اور اسے
قرآن کے لیے مشکل رستہ کیوں اختیار کیا.89 الہام الہی کا نام دے دیا.10 اس وسوسہ کا جواب کہ قرآن کریم بعض آیات 19 اس وسوسہ کا جواب کہ رسول کریم کے تمام اخلاق
صرف ایک صحابی کے علم میں تھیں باقی کو ان کا محض کامیاب ہونے کا ایک ذریعہ تھے.20 اس وسوسہ کا جواب کہ نبی کریم نے اپنی مرضی
75
94
علم نہ تھا.11 اس وسوسہ کا جواب کہ حضرت ابوبکر نے جو سے قرآن کریم مرتب کیا ہے.نسخه قرآن تیار کیا وہ مرکزی اہمیت کا حامل 21 اس وسوسہ کا جواب کہ سورتوں کی ترتیب صحابہ
نہیں تھا.96
نے لگائی ہے.137
140
148
177
178
Page 422
الذكر المحفوظ
vi
22 اس وسوسہ کا جواب کہ قرآن کریم کے مختلف 34 اس وسوسہ کا جواب کہ حضرت ابی بن کعب کا
نسخوں میں آیات کی تعداد مختلف ہے.179
نسخہ قرآن موجودہ نسخہ سے مختلف تھا.23 اس وسوسہ کا جواب کہ سورتوں کی ترتیب حضرت 35 اس وسوسہ کا جواب کہ حضرت عثمان کے دور
194
میں قرآن کریم کے بارہ میں بہت اختلاف
عثمان نے لگوائی.24 اس وسوسہ کا جواب کہ جس نے بھی قرآن کریم ہو گیا.اس پر آپ نے بہت سے باہمی
مدون کیا ہے اس نے زیادہ لمبی سورتیں شروع مختلف نسخہ ہائے قرآن میں سے ایک رائج
205
کر دیا اور باقی جلوا دیے.میں رکھی ہیں.25 اعتراض کہ قرآن کریم کی ترتیب نزول بدل 36 اس وسوسہ کا جواب کہ آنحضور کے بعد قرآن کریم
207
کی مختلف قرآتیں رائج تھیں جو دراصل قرآن
281
285
دی گئی.26 اس وسوسہ کا جواب کہ قرآن کریم ایک بے ربط کریم کے متن میں اختلات کو ظاہر کرتی ہیں.286
221 37 اعتراض حضرت عمرؓ اور حضرت حکیم بن ہشام کا
اور بے ترتیب کلام ہے.27 اس وسوسہ کا جواب کہ قرآن کریم کے مضامین اختلاف قرآت کیوں ہوا جب کہ دونوں
236
ایک ہی قبیلہ سے تھے؟
میں کوئی ترتیب نہیں ہے.28 اس وسوسہ کا جواب کہ قرآن کریم میں واقعات 38 اگر مصحف امام دراصل مصحف ام کی بعینہ نقل تھا
کو اُن کی ظاہری اور تاریخی ترتیب کے مطابق تو پھر حضرت عثمان کی اس ہدایت کا کیا
بیان نہیں کیا گیا.مطلب ہے جو انہوں نے مصحف الامام کی
29 اعتراض کا جواب کہ قرآن کریم میں اعادہ اور تیاری کے وقت دی کہ اگر کوئی اختلاف ہوا تو
248
252
قریش کی قرآت پر لکھنا.تکرار پائی جاتی ہے.30 اس وسوسہ کا جواب کہ آیات رجم قرآن کریم کا 39 اعتراض کہ مختلف قرآتیں حفص اور ورش وغیرہ
تو اب بھی جاری ہیں.پھر حضرت عثمان نے
256
حصہ تھیں مگر درج نہ کی گئیں.31 اعتراض کہ اگر آیات رجم قرآن کا حصہ نہیں تھیں کون سا اختلاف ختم کیا؟
تو پھر رسول کریم اور خلفاء راشدین نے کیوں 40 اس وسوسہ کا جواب کہ حضرت عثمان کے جمع کیے
رجم کی سزا دی.261
گئے نسخہ قرآن میں اعراب اور نقطے نہیں تھے.293
297
303
32 اس وسوسہ کا جواب کہ کچھ آیات متن قرآن کریم جب لگائے گئے تو مختلف قرآتیں بن گئیں.305
کا حصہ نہیں تھیں لیکن شامل کردیں گئیں مثلاً 41 اس وسوسہ کا جواب کہ موجودہ دور میں عالم
سورۃ الفاتحہ اور معوذتین.271
اسلام میں دو قسم کے قرآن رائج ہیں.33 اس وسوسہ کا جواب کہ صحابہ کے نسخہ ہائے قرآن 42 اس وسوسہ کا جواب کہ مسلمانوں نے قرآن
کریم میں کثرت سے لفظ ”قل“ شامل
ایک دوسرے سے مختلف تھے.269
307
Page 423
الذكر المحفوظ
کر دیا ہے.311
314
vii
حصہ نہیں ہو سکتی.323
43 اعتراض کہ مترجمین تراجم میں اپنی طرف سے 49 اس وسوسہ کا جواب کہ بعض مسلمان بھی قرآن کریم
ایسے الفاظ شامل کر دیتے ہیں جو متن قرآن میں الحاقی آیات کی موجودگی کے قائل ہیں.323
میں موجود نہیں ہوتے.اس وسوسہ کا جواب کہ اکثر محققین کے خیال میں
44 اس وسوسہ کا جواب کہ علامہ سیوطی کے نزدیک 50 حضرت عثمان نے قرآن کریم میں سیاسی منفعت
قرآن کریم کے پانچ مقامات کے بارہ میں حاصل کرنے کے لیے آیات شامل کر دی ہیں.333
شک ہے کہ یہ حصے متن قرآن کا حصہ نہیں.14 51 اس وسوسہ کا جواب کہ اہل تشیع کے نزدیک
45 اس وسوسہ کا جواب کہ قرآن کریم متن کے بعض حصوں
کا سٹائل بتاتا ہے کہ یہ بعد میں شامل کیے گئے ہیں.16 52 اس وسوسہ کا جواب کہ قرآن کریم حفظ کرنے
سے ذہنی صلاحیتوں پر بُرا اثر پڑتا ہے.46 اس وسوسہ کا جواب کہ قرآن کریم متن میں شامل
قرآن کریم میں رد و بدل ہوا ہے.337
352
53 اس وسوسہ کا جواب کہ قرآن کریم کی بعض بعض الفاظ واضح طور پر رسول کریم کے اپنے آیات منسوخ ہو چکی ہیں.الفاظ ہیں.319
383
54 اعتراض کہ قرآن کریم کی تعلیم پندرہ سو سال قبل 47 اس وسوسہ کا جواب کہ محققین کے نزدیک قرآن
کریم کی بہت سی آیات الحاقی ہیں.48 اس وسوسہ کا جواب کہ سورۃ یوسف قرآن کریم کا
321
نازل ہوئی تھی.آج کے مسائل کا حل کیونکر
پیش کر سکتی ہے.398
Page 424
viii
انڈیکس اسماء
[254] [261] [264] [271] [278]
[280] [181] [283] [284] [295]
[297] [298] [301] [302] [314]
[323] [324] [336] [339] [344]
[349] [358] [391]
[190]
[133] [134] [221]
ابوبکر انباری
ابو جہل
ابو دردا
[21] [25]
[21] [25]
[20] [35]
ย
ابوزید
ย
ابوسعید
ابوسفیان
[112] [113] [122] [132] [133]
[173]
[255]
[227]
[54]
[35]
ابو عبداللہ محمد بن احمد القرطبی
ابو علی احمد بن جعفر دینوری
ابو موسیٰ الاشعری
ابونضرة
ابی بن کعب
[10] [21] [22] [25] [27] [52] [189]
[190] [274-276] [281] [283] [284]
[50]
[43] [303]
ابی عمران
أم سلمة
[22]
[65] [358]
[89][107] [187] [199]
[2] [25] [58] [341]
ابان
این آنزی
ابن حجر
ข
ابن سعد
ابن عباس
[25] [33] [157] [256] [287] [299]
ابن وراق (Ibn Warraq)
[9] [10] [11] [14] [26] [27] [57]
[70] [71] [73] [76] [105] [109]
[111-114] [118] [119] [122] [131]
[164] [173] [174] [179-181] [205]
[207] [218] [221] [222] [225]
[227] [228] [235] [248] [252]
[253] [256] [257] [261] [268]
[281] [286] [305] 307-310]
[314-316] [319] [320] [323-326]
[331-333] [335] [337] [340] [345]
[350-354] [357-363] [384] [394]
[100] [101]
ابوالاسود دولی
ابوالفضل بن الحسن الطبرسی
[26] [189] [190] [338] [339]
[41]
ابوامامہ باہلی
ابو بکر
[10] [17] [20] [22] [28] [48] [72]
[76] [77-89] [91-93] [95] [96] [98]
[99] [101] [128] [129] [154-156]
[185] [191] [193-195] [198-204]
Page 425
انس
[21] [25] [43] [51] [56] [113]
[114] [232] [273] [303] [388]
[101] [112] [301] [344]
ย
امیر معاویہ
امیہ بن خلف
اوس ثقفی
[164] [165]
[21] [196]
[121] [323]
ایڈورڈ ھیڈ ( Edward Said)
ایچ.اے.آرگب (H.A.R.Gibb)
[345]
ایچ.ایم.ہینڈمن (H.M.Hyndman
[99] [100]
اینڈریورپین (Andrew Rippen)
[29]
اے.لیونارڈ (Major A.Leonard)
أَيُّوبَ بْنِ مُوسى
[159]
با سورتھ سمتھ (Basworth Smith)
[41]
بدرالدین محمد بن عبد الله الزرکشی علامه
[57] [58] [345]
[12] [80] [196] [199] [200]
ย
براء بن عازب
[44]
بلال بن رباح
ثابت بن قیس بن شماس
[164] [188] [189]
Ĉ
[23]
ix
ج
جان برشن (John Burton)
[197] [299] [346] [347]
[127] [157] [158] [159] [161]
جان ڈیون پورٹ (John Davenport)
[170]
جہم بن صلت
[23]
جیفری لینگ (Jeffery Lang)
[123] [323]
م
حذیفہ بن یمان
حذیفہ ثقفی
[23]
[21] [196]
خر
خالد بن سعید
[17]
خالد بن ولید
[23][163]
خباب بن الارت
ریونڈ وھیری
ز
زبیر بن العوام
[165] [166]
[16]
[22]
Page 426
عائشة
X
زید بن ثابت
[23] [26] [34] [46] [56] [162]
[167] [168] [184] [186] [187]
[256-258] [264] [268] [269] [270]
[277] [312] [367]
[19-22] [24] [25] [77] [78] [80]
[82] [83] [85-88] [91] [96] [98]
[117] [185] [187] [191] [200]
[253] [262] [263] [266] [290]
[297] [298] [344]
[22]
[22]
[344]
عبد اللہ بن ارقم زھری
عبد اللہ بن رواحہ
[27] [52]
سالم
سٹینلی لین پول ( Stanley عبداللہ بن زبیر
عبد اللہ بن سبا
[324] [325]
عبد الله بن سعد ابی سرح
[22] [109-115] [1171119] [122]
[325] [] [] [] [] [] []
عبد اللہ بن سعد
[22]
عبد اللہ بن عباس
[178]
عبد اللہ بن عبد اللہ بن ابی بن سلول
[22]
عبد اللہ بن عمر
[19] [33] [44] [51] [195] [255] []
[] [] []
[35] [214]
عبداللہ بن عمر و
عبد اللہ بن مسعودؓ
(Lane-Poole
[150] [159] [167]
[55]
[23]
[118] [190] [258]
سهل بن معاذ جهنى
سعید بن جبیر
علامه سید محمود آلوسی
علامہ سیوطی
[81] [87] [88] [94] [102] [188]
[191] [194] [196] [197] [199]
[227] [314] [321] [337]
[22]
[347]
[25] [27] [41] [51] [52] [154]
[164] [186] [189] [190] [269]
[270] [271] [274-281] [284] [287]
[293] [299] [301] [302] [313]
[325] [] []
[18] [23]
[42]
[56]
شرجیل بن حسنة
شوالی (Schwally)
عامر بن فہیرہ
عامر بن واثلہ
Page 427
[25] [43] [303]
قادة
کیرم آرمسٹرانگ
[15] [38] [58] [121] [219] [220]
[226] [322] [341]
کینتھ گریگ (Kenneth Cragg)
لات
لا
[37] [347]
[145] [164]
لمارٹن ( فرانس دے مارٹن )LaMartine
[171] [355]
[216-218] [335]
لبید بن ربیعہ عامری
xi
[10] [17] [22] [26] [55] [77] [80]
[81] [89] [95] [96] [98-101] [112]
[178] [185] [191] [194] [198-201]
[203] [255] [270] [271] [283]
[285] [294-303] [305] [306] [308]
[321] [323-325] [333] [334] [336]
[337] [339] [343] [344] [346]
[391]
[109] [110] [145] [164]
[42]
[22]
ย
عثمان
عزمی
عقبہ بن عامر تختی
علاء بن حضرمی
[17] [20] [22] [26] [100] [142]
[194] [200] [201] [268] [296]
[301] [321] [323-325] [333-335]
[337-339] [342] [344]
[110] [111] [113]
علی دانشی
عمر بن الخطاب
مرزا بشیر احمد صاحب
[12] [30] [72] [206] [210] [246]
مرزا بشیر الدین محمود احمد
[4] [27] [29] [35] [36] [38] [46]
[52] [68] [72] [73] [78] [90] [105]
[125] [155] [205] [223] [244]
[253] [266] [278] [281] [288]
[291] [318] [370] [379] [381]
[389] [397]
[18] [19] [32] [46] [48] [50] [51]
[56] [71] [72] [77-88] [90] [92]
[96] [98] [117] [164] [165] [168]
[203] [216-218] [256-259]
[261-264] [270] [287] [293] [293]
[294] [297] [335] [358] [] []
[23] [35] [214] []
عمر و بن العاص
[60][185] [362] [380]
ย
مرزا طاہر احمد
مرزا غلام احمد
[7] [14] [39] [42] [45] [48] [236]
[237] [239] [240] [242] [243]
[249] [261] [368] [370] [382]
[73] [359] [380]
ข
مرزا ناصر احمد
ف
فاطمه ( بنت الخطاب)
(
فاطمة بنت محمد الله
[18]
[48] [128] [134] [184] [265]
Page 428
xii
موریس بوکائیے (Dr.Maurice Bucaille) مرقس ڈاڈز ڈاکٹر (Dr.Marcus Dods)
مزنی
محمد (Mohammad) ()
[158]
موسى
[37] [76] [95][108] [197] [348]
[37] [73] [142] [167] [249]
میر محموداحمد ( پرنسپل جامعہ احمدیہ)
[353]
[56] [358]
[133]
نافع بن عبد الحارث
نضر بن الحارث
نورالدین خلیفة اصبح الاول
[65] [201][359]
واشنگٹن ایروینگ (Washington Irving)
[61][134] [135]
[217] [218]
ولید بن مغیره
ویلم گراہم (William Graham)
[24]
ویم میور (William Muir)
[75] [120] [129] [300] [334] [347]
[348] [384]
ہشام بن حکیم بن حزام
[32] [50] [51] [164] [287] [293]
[294]
[43] [304]
[26] [189] [339]
[10] [15] [16] [26] [34] [36-38]
[57] [59] [65] [68] [69] [73] [74]
[76] [105] [106] [108] [109] [112]
[113] [119] [120] [124-127] [129]
[131-134] [136] [140] [150] [157]
[158] [161-164] [167] [169] [171]
[173] [177] [179] [197] [198]
[208] [210] [217] [219] [221]
[256] [257] [260] [300] [310]
[311] [315-319] [342] [344-348]
[350] [355-357] [362] [375] [378]
[382] [397]
[71]
محمَّد بْن كَعْب القرظي
[23]
[29] [81]
[21] [25] [27] [52] [117]
[22]
[22]
[23]
محمد بن مسلمة
مسیلمہ
معاذ بن جبل
معاویہ بن ابی سفیان
معیقیب بن ابی فاطمہ
مغیرہ بن شعبہ
مقوقس
[30] [74] [75]
منٹگمری واٹ (Montgomery Watt) يغلى بن مُمَلِك
[147]
ى
[37]
منفتاح "Merneptah"