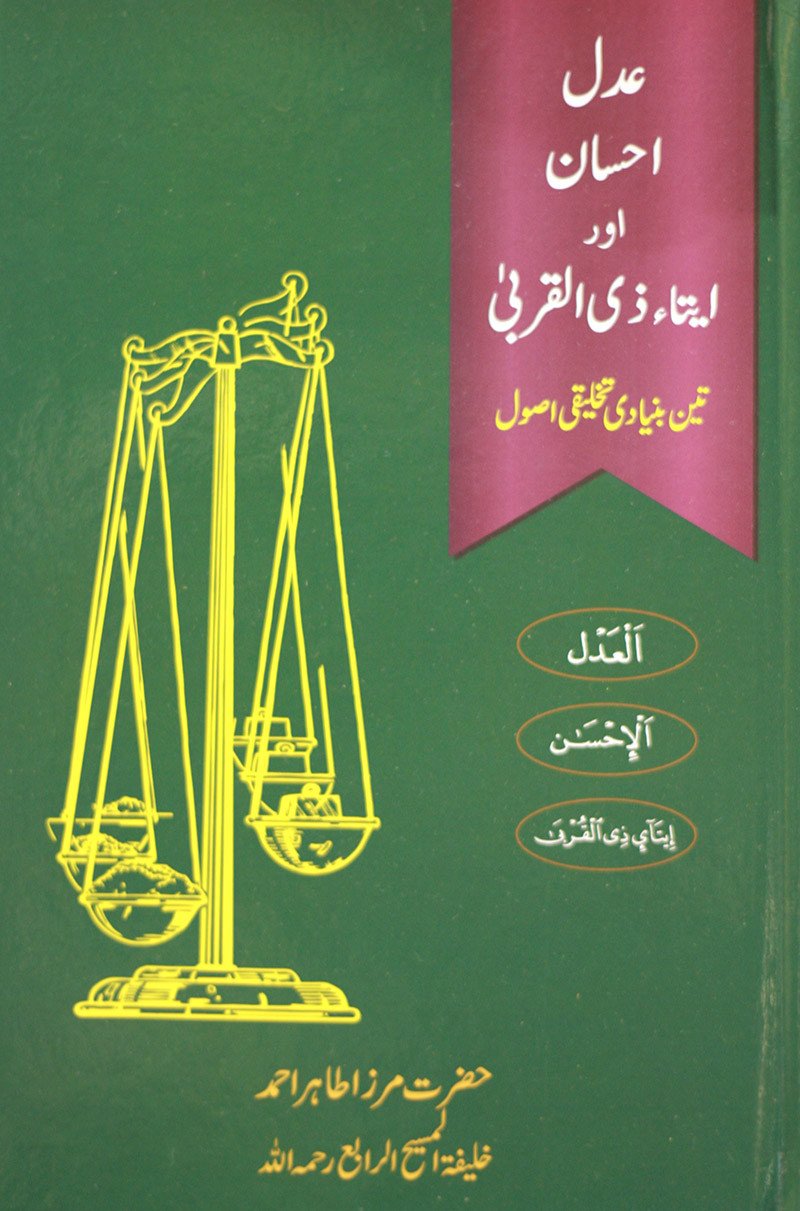Complete Text of Adl Ihsan
Content sourced fromAlislam.org
Page 1
عدل، احسان
اور
ايتاء ذى القربى
حضرت مرزا طاہر احمد
خليفة المسيح الرابع رَحِمَةُ الله تَعَالَى
2009
ISLAM INTERNATIONAL PUBLICATIONS LIMITED
Page 2
عدل، احسان اور ایتا عذی القربی
(Adl, Iḥsān aur ītā'i Dhil Qurbā)
Urdu translation of 'Absolute Justice, Kindness and Kinship'
by Hadrat Mirza Tahir Ahmad (1928-2003),
Khalifatul Masih IV, Head of the Ahmadiyya Muslim Jamā‘at.O Islam International Publications Ltd.Published in 2009 by:
Islam International Publications Ltd.'Islamabad' Sheephatch Lane,
Tilford, Surrey GU10 2AQ,
United Kingdom.Printed in U.K.at:
No part of this book may be reproduced or transmitted in
any form or by any means, electronic or mechanical,
including photocopy, recording or any information
storage and retrieval system, without prior written
permission from the Publisher.ISBN: 1 85372 740 7
Page 3
مصنف کا تعارف
حضرت مرزا طاہر احمد رحمہ اللہ تعالیٰ قادیان میں حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ عنہ اور
حضرت مریم بیگم صاحبہ نوراللہ مرقدھا کے ہاں 1928ء میں پیدا ہوئے آپ نے ابتدائی تعلیم
قادیان میں حاصل کی اور 1944ء میں اپنی والدہ محترمہ کی وفات کے چند ماہ بعد گورنمنٹ کالج
لاہور میں داخل ہوئے.آپ 1955ء میں پہلی دفعہ اپنے والد صاحب کے ہمراہ انگلستان تشریف
لے گئے اور انہی کی ہدایت کے مطابق انگریزی زبان کے علم کو بڑھانے اور یورپ کے معاشرتی
اقدار کے مطالعہ کے لئے وہیں ٹھہر گئے.آپ نے SOAS یونیورسٹی آف لنڈن میں داخلہ لیا
جہاں آپ نے اڑھائی سال تک تعلیم حاصل کی.1957ء کے اواخر تک آپ انگلستان، آئرلینڈ،
سکاٹ لینڈ، ویلز اور مغربی یورپ کا اکثر حصہ دیکھ چکے تھے.آپ کی رسمی تعلیم تو فقط یہاں تک تھی.لیکن آپ کی وسعت مطالعہ کی کوئی انتہاء نہ تھی اور مضامین نہایت دقت نظر کے ساتھ آپ کے زیر
نظر رہتے تھے.بعد میں جب آپ جماعت احمدیہ کے امام منتخب ہوئے تو آپ کی عالمی ذمہ داریوں کی
ادائیگی میں یہ نصابی اور غیر نصابی تجربات اور علوم بہت مفید ثابت ہوئے.آپ 1982ء میں حضرت
حافظ مرزا ناصر احمد خلیفتہ اسیح الثالث نور اللہ مرقدہ کی وفات کے اگلے روز جماعت احمدیہ کے امام
منتخب ہوئے.جنرل ضیاء الحق کے اینٹی احمد یہ آرڈینینس مجریہ 26 اپریل 1984 ء نے آپ کو
پاکستان چھوڑنے پر مجبور کر دیا چنانچہ آپ مورخہ 30 اپریل 1984ء کو انگلستان تشریف لے گئے.جہاں آپ 19 اپریل 2003 ء تک تادمِ وفات قیام پذیر رہے.یہیں سے آپ نے عالمی
جماعت ہائے احمدیہ کی رہنمائی اور کروڑوں مردوں عورتوں اور بچوں کی اس رنگ میں تربیت فرمائی
جس سے ان میں زندگی کی ایک نئی لہر دوڑ گئی اور چند ہی سالوں میں جماعت کی تعداد کروڑوں تک
پہنچ گئی اور 175 ممالک میں جماعت ہائے احمدیہ کا قیام عمل میں آ گیا.اسی دوران MTA کا قیام عمل میں آیا جو آپ کی شب و روز محنت کا ثمر ہے.جس کے ذریعہ
دنیا بھر میں خطبات، مجالس عرفان اور دیگر علمی اور روحانی پروگرام پیش کئے جارہے ہیں.ایک روحانی رہنما ہونے کے علاوہ آپ ایک عالم بے بدل، اردو اور انگریزی کے عدیم المثال
مقر ر اور بہت سی کتابوں کے مصنف تھے جن میں یہ کتاب بھی شامل ہے.آپ اعلی پایہ کے شاعر
بھی تھے.
Page 4
اِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَ ايْتَائِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى
عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ
(النحل 91:16)
یقیناً اللہ عدل کا اور احسان کا اور اقرباء پر کی جانے والی عطا کی طرح
عطا کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی اور ناپسندیدہ باتوں اور بغاوت سے
منع کرتا ہے.وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تا کہ تم عبرت حاصل کرو.
Page 5
8
9
15
18
22
22
له الحالم به چه الله له چه په چه پیا الله لا مه چ نه نه جم
22
23
24
25
27
28
31
32
34
40
42
42
44
45
3
5
LO
5
V
X
پیش لفظ
1- تین بنیادی تخلیقی اصول.....انسانی تعلقات کے تین مدارج.قرآن کریم کی جامع ترین آیت.فہرست مضامین
حصہ اوّل
آیت کے مضامین کا عالم نباتات اور عالم حیوانات پر اطلاق.توازن پیدا کرنے والے قانون کو چلانے والا رہنما اصول.-2 تخلیق کائنات.کشش ثقل کا عالمگیر قانون.3 زمین کا ماحولیاتی نظام.زمین اور اجرام فلکی کے مابین توازن.زمین کا ہوائی کرہ
زیریں کرہ ہوائی (The Troposphere)
بالا ئی کرہ ہوائی (The Stratosphere)
مقناطیسی کرہ ہوائی (The Magnatosphere).زمین.پہاڑ.فضائی گیسوں کا باہمی توازن.عالم نباتات اور عالم حیوانات کا باہمی توازن
4 عالم حیوانات...عدل، احسان اور ایتا عذی القربی کے تعلق میں احساس کا کردار.5- انسانی ارتقا کا اگلا قدم
انسان بطور عالم صغیر
زندگی کے بنیادی اجزائے ترکیبی.توازن اور آگہی.
Page 6
vi
6 انسانی جسم کا اندرونی توازن.اچھے اور برے کی اندرونی کسوٹی..جسمانی نشو ونما...........بیماری کے خلاف حفاظتی تدابیر.انسولین کی پیداوار میں احسان کا کردار
کیلشیم
سوڈیم اور پوٹاشیم.خلیات کی تقسیم کا عمل
عالم حشرات پر ایک نظر..عدم توازن اور بیماری..حفاظت پر مامور فرشتے.انسان کی بے اعتدالیاں.7- عدل سے انحراف..عقیدہ تثلیث
عدل کی خلاف ورزیوں پر متنبہ کرنے والا نظام.مذہب
کی تشکیل میں تین تخلیقی اصولوں کا کردار.حضرت آدم علیہ السلام کا دور.حضرت آدم علیہ السلام کی جنت.نبوت کا اپنے کمال کی طرف سفر.تعلیمات عدل کا ارتقا.9- اسلام: مذہبی تعلیمات کا منتہی.اسلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ترقی یافتہ
راه اعتدال.صراط مستقیم.اسلام اور فطرت انسانی.احتساب اور موروثی گناہ
بنی نوع انسان کیلئے ہدایت.حوالہ جات حصہ اوّل.عدل، احسان اور ایتاء ذی القربی
47
47
49
53
54
56
58
59
60
61
62
63
64
65
به من دل لا لا لا لا 8 و 8
67
71
71
74
77
80
83
83
85
86
89
93
97
99
Page 7
10- مذہب میں آزادی ضمیر.11 - اسلامی جہاد کے متعلق غلط نہیں.حصہ دوم
12- عبادت میں عدل، احسان اور ایتاء ذی القربیٰ کا مقام.فلسفه دعا....مساجد کی آفاقیت.عبادت میں اعتدال..عبادت کی اقسام.13- عدل کا قیام بہر حال ضروری ہے
14- امانت اور احتساب.15.مسلمانوں اور غیر مسلموں کی ایک دوسرے کے خلاف شہادت...........حوالہ جات حصہ دوم..اسلام میں نظام شہادت
حصہ سوم
16- مالی لین دین کی شہادات.17- اللہ تعالیٰ.فرشتوں اور صاحب علم بندوں کی گواہی کا نظام.دہریوں کے لئے اللہ تعالیٰ کی ہستی پر گواہی
کائنات کی شہادت.18.ایک نئی قسم کی شہادت
نبیوں کی شہادت ایک دوسرے کے حق میں.ایک مسلمہ اصول جس کا اطلاق ایسے تمام معاملات پر ہوتا ہے جہاں شہادت قبول یارڈ کی جاتی ہے.آنحضرت ﷺ کے حق میں ماضی کی شہادت کے علاوہ مستقبل کی شہادت.آنحضرت ﷺ کی صداقت پر اس دور کی ایک ناقابل تردید شہادت جب آپ نے دعوی کیا.ﷺ پراس دور کی ناقابل نے.19 - کائنات میں خدا کا ریکارڈنگ سسٹم..20- بندہ سے خدا کا معاہدہ اور ذیلی معاہدات.ميثاق النبيين..اہلِ کتاب سے
105
113
vii
121
126
137
138
140
142
144
151
158
163
165
168
170
172
175
176
178
179
181
183
188
191
193
Page 8
viii
قومی معاہدہ کی خلاف ورزی کی سزا.جرم اور سزا میں باہمی مناسبت.نقض عہد کی مزید سزائیں.عدل، احسان اور ایتاء ذی القربی
196
198
199
201
202
203
205
207
208
208
211
213
214
215
217
223
223
225
226
227
227
229
230
231
231
232
ایفائے عہد کی جزاء.جیسی اخلاقی تعلیم انسانوں کو دی گئی ویسی ہی تعلیم کا اللہ تعالیٰ خود اپنے آپ کو پابند کرتا ہے.انفرادی معاہدات.انفرادی معاہدہ اور عہد شکنی کی سزا.21.غیروں سے معاہدات
غیروں سے معاہدات کی دو قسمیں
معاہدہ صلح حدیبیه.میثاق مدینہ
معاہدات کی پابندی میں اسوہ رسول ﷺ
مسلمانوں کے سیاسی ادبار سے متعلق ایک پیشگوئی.معاہدات کی پابندی کی بعض اور مثالیں.حوالہ جات حصہ سوم.22- قول میں عدل
قول عدل کی پہلی خصوصیت.حصہ چہارم
آنحضرت ﷺ کی زندگی میں قول عدل کی مثالیں.قول عدل کی دوسری خصوصیت.قول عدل کی تیسری خصوصیت
قول عدل کی چوتھی خصوصیت.23- بنی نوع انسان کے مابین قیام عدل کا بنیادی اصول.نسلی برابری کا ایک عظیم الشان چارٹر..Racialism کی بیماری کی جڑ
Racialism سے بچاؤ کیلئے قرآن کریم کی حکیمانہ تعلیم.آنحضرت کا طریق تربیت.
Page 9
ix
233
234
235
237
237
237
243
244
244
246
247
247
249
250
251
252
253
254
254
256
257
258
261
بین الاقوامی جھگڑوں کے فیصلہ کیلئے قرآن کی عادلانہ تعلیم.قرآنی تعلیم کی خلاف ورزی کے نتیجہ میں آئندہ جنگوں کا خطرہ.بلا امتیا ز تمام بنی نوع انسان کے معاملات میں نیکی کی قرآنی تعلیم
24- رشتہ داروں کے متعلق عدل و احسان کی تعلیم.والدین کے بچوں پر حقوق.والدین کے ساتھ احسان کا تاکیدی حکم.والدین کی وفات کے بعد بھی ان سے حسن سلوک جاری رکھنے کی حسین تعلیم
وفات یافتہ والدین کیلئے استغفار
اولاد کے والدین پر حقوق.قتل اولاد کے خلاف قرآنی تعلیم کی عظیم حکمت
اولاد کے مابین عدل
کی تعلیم.اولاد سے عدل کی جزا.عدل کے بعد اولاد کے ساتھ احسان کی تعلیم.کوئی اپنے بچہ کو بھی اسکی مرضی کے بغیر وقف نہیں کر سکتا.تکریم اولاد کی حسین تعلیم.یتامی کے حقوق
یتامی کے بارہ میں احسان کی تعلیم
یتامی کے متعلق آنحضرت ﷺ کا طرز عمل
اقرباء کے حقوق.صلہ رحمی کی عظیم الشان پر حکمت تعلیم.صلہ رحمی ، رحم اور رحمانیت
کا باہم تعلق..حوالہ جات حصہ چہارم.انڈیکس
Page 10
X
عدل، احسان اور ایتاء ذی القربی
پیش لفظ
حضرت صاحبزادہ مرزا طاہر احمد صاحب خلیفہ المسیح الرابع امام جماعت احمد یہ عالمگیر
(1982ء تا2003ء) نے 1982ء میں مسند خلافت پر متمکن ہونے کے بعد جلسہ سالانہ ربوہ
پاکستان کے موقع پر اردو میں
اسلام کا نظام عدل، احسان اور ایتاء ذی القربی
کے عنوان سے خطابات کا ایک سلسلہ شروع فرمایا.اس سلسلہ کا دوسرا خطاب آپ نے جلسہ سالانہ
ربوہ پاکستان کے موقع پر 1983ء میں ارشاد فرمایا.1984ء میں بوجوہ آپ کو انگلستان ہجرت
کرنا پڑی جہاں آپ نے جلسہ سالانہ انگلستان کے موقع پر دو مزید خطابات ارشاد فرمائے جن میں
سے پہلا یعنی اس سلسلہ کا تیسر ا خطاب 2 اگست 1987ء کو اور دوسرا یعنی اس سلسلہ کا چوتھا اور آخری
خطاب 24 جولائی 1988 ء کو ارشاد فرمایا.اس عنوان پر پہلے خطاب کا انگریزی میں ترجمہ کیا گیا جسے اسلام انٹرنیشنل پبلیکیشنز لمٹیڈ انگلستان نے
Absolute Justice, Kindness and Kinship - The Three Creative Principles
کے عنوان سے 1996ء میں شائع کیا.بعد ازاں حضور انور نے چاروں خطابات کے مسودات کی
خود نظر ثانی کرتے ہوئے ان میں متعدد اضافے اور تبدیلیاں فرمائیں.چونکہ خطابات کے تسلسل
میں کافی وقفہ آ گیا تھا جس کی وجہ سے ابتدائی دو اور آخری دو خطابات میں مضامین کی اچھی خاصی
تکرار ہو گئی تھی اس لئے حضور انور نے انگریزی متن کی خود نظر ثانی کرتے ہوئے کئی حصوں کو مختصر کر دیا
اور کئی ایک حصے متن سے خارج کر دیئے تا کہ غیر ضروری تکرار قاری پر گراں نہ گزرے نیز مضمون کا
تسلسل بھی برقرارر ہے.حضور نے محترمہ فرینہ قریشی صاحبہ اور محترمہ فوزیہ احمد صاحبہ کو پہلے دو خطابات کا انگریزی ترجمہ
بذات خود از سر نولکھوایا.جن کو مد نظر رکھتے ہوئے مکرم و محترم چوہدری محمد علی صاحب وکیل التصنيف
کی زیر نگرانی اردو تر جمہ کو ان کے مطابق کیا گیا.
Page 11
xi
خاکسار نے محض خدا تعالیٰ کے فضل سے مہینوں تک روزانہ کئی کئی گھنٹوں حضور انور کی خدمت میں
حاضر ہوکر اس کتاب پر کام کرنے کی توفیق اور سعادت پائی.حضور انور نے چاروں خطابات کے
مسودات کا بنظر غائر جائزہ لیا.اس کا طریق یہ تھا کہ خاکسار مسودہ پڑھتا جاتا اور حضور انور قطع نظر اپنی
بیماری کے مناسب مواقع پر ہدایات دیتے جاتے اور مناسب حال صحیح اور تبدیلی فرماتے جاتے.محترمه فرینه قریشی صاحبہ اور فریدہ احمد صاحبہ نے بھی کئی ماہ تک گھنٹوں حضور سے ہدایات لینے کی
سعادت پائی اور حضور کی ہدایات کے مطابق مسودہ پر کام کیا.اسی طرح مندرجہ ذیل احباب نے بھی
حضور کی ہدایات کے مطابق ان خطابات کے بارہ میں حوالہ جات وغیرہ کے حصول میں خدمت کی
توفیق پائی.منیر احمد جاوید صاحب، پیر محمد عالم صاحب (مرحوم)،
مسر صالحہ صفی صاحبہ اور مسز فوزیہ باجوہ صاحبہ.حوالہ جات وغیرہ کی چیکنگ اور کتاب کی سیٹنگ کا کام مکرم و محترم صاحبزادہ مرزا انس احمد
صاحب وکیل الاشاعت نے بڑی محنت سے کیا.اللہ تعالیٰ اُن سب کو جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں
نے کسی بھی رنگ میں خدمت کی توفیق پائی ہے.مجھے دکھ ہے کہ بالآخر مسودہ نے جب حتمی شکل اختیار کی تو بعض ناگزیر وجوہات کی بناء پر یہ
کتاب حضور کی زندگی میں شائع نہ ہوگی.غم اور خوشی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ آج ہم حضرت
مرزا مسرور احمد صاحب خلیفہ اسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کی زیر ہدایت ونگرانی اس
کتاب کی اشاعت کی توفیق پارہے ہیں.فالحمد لله على ذالك
اب پہلی بار چاروں خطابات کو ایک جلد میں اکٹھا پیش کیا جارہا ہے.فہرست مضامین کو کتاب
کے شروع میں اور انڈیکس کو آخر پر رکھا گیا ہے.اور دراصل یہ حضرت خلیفتہ امسیح الرابع رحمتہ اللہ علیہ
کی خواہش اور ہدایات کے مطابق کیا گیا ہے.حضور انور کے ان خطابات کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے بیان فرمودہ
نظام عدل، احسان اور ایتاء ذی القربیٰ جیسے سنہری اصول اپنی جامعیت کے اعتبار سے مخلوق خدا کے
Page 12
xii
عدل، احسان اور ایتاء ذی القربی
ہر پہلو کا احاطہ کیے ہوئے ہیں.نیز کوئی بھی چیز ان کے دائرہ عمل سے باہر نہیں ہے.گویا ہر ایک واقعہ
نیز جسمانی، اخلاقی، روحانی اور سماجی ہر ایک عمل کے حاکم اصول یہی ہیں.ان اصول کی عدم
موجودگی سے نظام کائنات درہم برہم ہو کر رہ جائے گا اور انسانوں کے باہمی تعلقات میں بگاڑ پیدا
ہو جائے گا.توازن، ترتیب اور ہم آہنگی، انتشار اور بدنظمی کا شکار ہو جائے گی.نہ صرف انسانی
معاشرہ کا تارو پود بکھر کر رہ جائے گا بلکہ زندگی کی کم ترین شکل یعنی غیر نامیاتی مادے بھی اپنا وجود کھو
دیں گے اور سائنسی قوانین بھی معطل ہو کر رہ جائیں گے.حضور انور نے یہ بحث بھی اٹھائی ہے کہ ان تین بنیادی اصول میں سے عدل سب سے بنیادی
کردار کا حامل ہے اور باقی دونوں اصول اسکا تکملہ ہیں اور عدل کے بغیر کام نہیں کر سکتے.اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس کتاب کی اشاعت ہر لحاظ سے بے حد با برکت فرمائے.آمین
منیرالدین شمس
ایڈیشنل وکیل التصنيف
لندن
دسمبر 2008
Page 13
عدل، احسان
اور
ايتاء ذى القربى
تین بنیادی متخلیقی اصول
حصہ اوّل
خطاب فرموده جلسہ سالانہ ربوہ پاکستان دسمبر 1982ء
حضرت مرزا طاهر احمد
خليفة المسيح الرابع رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى
1- تین بنیادی متخلیقی اصول
2- تخلیق کا ئنات
3- زمین کا ما حولیاتی نظام
4- عالم حیوانات
5 انسانی ارتقا کا اگلا قدم
6- انسانی جسم کا اندرونی توازن
7- عدل سے انحراف
8- مذہب کی تشکیل میں تین تخلیقی اصولوں کا کردار
- اسلام مذہبی تعلیمات کا منتہی
Page 15
تمهيد
3
آج صبح جب میں نماز کیلئے نکلا تو بارش کے نمایاں آثار دیکھ کر معامیں نے اپنے دل کو ٹولا کہ
کہیں میرے دل میں خدا نخواستہ کسی قسم کا کوئی شکوہ تو راہ نہیں پا گیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ آج جلسہ
سالا نہ کا دن تھا اور بارش کے تیور بظاہر ایسے تھے کہ اگر یہ پورے زور سے جم کر برسنے لگتی تو جلسہ
یقیناً درہم برہم ہو جاتا اور اس کے انعقاد کی کوئی صورت نہ رہتی.لیکن دل سے بے اختیار حد نکلی کیونکہ
دل کے کسی گوشے میں بھی شکوے کا شائبہ تک نہیں تھا بلکہ شکر ہی شکر تھا.معا میری طبیعت حمد کے
ساتھ محسن اعظم ، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی طرف مائل ہوئی.قرآن کریم ہمارے اندر
خدا تعالیٰ کی کامل فرمانبرداری کی روح پیدا کرتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایسے کامل فرمانبردار
بندوں کی زیادہ سنتا ہے اور ان پر بے شمار فضل نازل کرتے ہوئے انہیں نیکیوں میں آگے بڑھنے کی
توفیق عطا فرماتا ہے.اس بات کو حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفہ اسیح الثانی رضی اللہ عنہ نے
اپنی ایک نظم میں بڑے حسین پیرائے میں یوں بیان
فرمایا ہے کہ:
ہو فضل تیرا یا رب! یا کوئی ابتلا ہو
راضی ہیں ہم اسی میں جس میں تری رضا ہو
یہی مضمون قرآن کریم میں ایک مختلف پیرایہ میں یوں بیان ہوا ہے:
أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ
(یوس 63:10)
ترجمہ: سنو کہ یقینا اللہ کے دوست ہی ہیں جن پر کوئی خوف نہیں
اور نہ وہ غمگین
ہوں گے.ہم پر اللہ تعالیٰ کا بے پایاں احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایسی جماعت میں شامل ہونے کی توفیق
عطا فرمائی ہے جس کے افراد ہمیشہ رضائے باری تعالیٰ پر راضی رہتے ہیں.اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ
کی اپنے عاجز بندوں کی حفاظت اسی حکمت کی بدولت ہے.اگر لوگ پوری طرح راضی برضا ر ہیں گے تو
وہ الہی نظام کے زندہ نشان بن جائیں گے.نہ تو وہ مغلوب ہوں گے اور نہ ہی ہلاک کئے جائیں گے.بعض دیگر جذبات نے بھی میرا دل حمد باری تعالیٰ سے بھر دیا جن میں سے ایک ہماری جماعت کا
غیر معمولی اخلاص ہے.میں جانتا ہوں کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت قربانی
پیش کرنے والی ایسی جماعت ہے کہ اگر اس کا امام انہیں کہے کہ آؤ اور برستی بارش میں بیٹھ جاؤ تو وہ
Page 16
4
عدل، احسان اور ایتاء ذي القربى - حصه اول
اطاعت گزاری میں لمحہ بھر کو بھی تر درد نہیں کریں گے بلکہ کامل فرمانبرداری سے دیوانہ وار دوڑتے ہوئے
آئیں گے.حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت کا یہی طرۂ امتیاز ہے.تاہم غریبوں،
کمزوروں اور لا چاروں کا خیال کر کے دل ایسا حکم دینے پر آمادہ نہیں ہوتا لیکن جہاں تک جماعت
احمدیہ کی قربانیوں کا تعلق ہے تو اس کا اظہار آج ایک دوست نے ایک ہی فقرے میں یوں کیا کہ یہ تو
ایسی جماعت ہے جس کے اخلاص اور قربانی کی روح سے ڈر لگتا ہے.حیرت انگیز اخلاص ہے.“
ہم ان لوگوں میں سے تو ہر گز نہیں جن کے متعلق یہ لطیفہ مشہور ہے کہ کسی جگہ سکھوں کی ایک ٹولی
کا گڈا کیچڑ میں پھنس گیا.انہوں نے ست سری اکال کے نعرے لگائے اور اپنے گروؤں کے نام
بھی لئے لیکن وہ گڈ انکل نہ سکا.اتفاق سے مسلمانوں کی ایک ٹولی گزر رہی تھی.اس نے بھی دھکا
لگایا اور ساتھ یا علی“ کا نعرہ بھی بلند کیا ، اس وقت تک چونکہ اور لوگ بھی دھکا لگانے میں شامل ہو گئے
تھے اس لئے گڈ انکل آیا.اس پر سکھ بہت پریشان ہوئے کہ مسلمانوں کے گرو کو زیادہ طاقتور سمجھا
جائے گا.لیکن مسلمانوں کے گرو کو صاف صاف خراج تحسین پیش کرنا بھی ان کے اپنے مذہبی
جذبات پر گراں تھا اس لئے انہوں نے یہ مشکل اس طرح حل کی کہ بجائے یہ اعتراف کرنے کے کہ
مسلمانوں کا گرو ہمارے گرو سے طاقتور نکلا، یہ کہ دیا کہ ہے تو ہمارا گر وہی طاقتور لیکن مسلمانوں کا
گر وکھو بے کانگڑا ہے.( یعنی گارے اور کیچڑ کا جہاں تک معاملہ ہے اس کے لحاظ سے ہمارے گرو پر
مسلمانوں کا گر و فوقیت لے گیا ہے.مترجم)
ہم ایسے کسی گرو کے مرید تو نہیں ہیں جس کی طاقت کا دائرہ محدود ہے بلکہ اس گرو کے مرید
ہیں جو ہر حال میں، ہر مشکل میں اپنی قوت میں بے مثال اور ہر چیز پر ایک نمایاں فوقیت اور امتیازی
شان رکھتا ہے.وہ ہمیں اندھیرے سے نکال کر نور کی طرف نکال کر لے جاتا ہے.اس کے ماننے
والے کسی حال میں ظلمات سے مرعوب اور مغلوب نہیں ہوتے بلکہ ہر حالت میں قدم آگے بڑھاتے
ہیں اور ایسے نہیں کہ جن کے متعلق قرآن کریم فرماتا ہے:
وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا ( البقرة 21:2)
ترجمہ: اور جب وہ ان پر اندھیرا کر دیتی ہے تو ٹھہر جاتے ہیں.اس کے برعکس وہ تو اندھیروں میں بھی چلنا جانتے ہیں اور روشنیاں ہوں تب بھی چلنا جانتے
ہیں، بارش ہو یا سخت دھوپ تب بھی قدم آگے ہی بڑھاتے ہیں.اس مضمون پر غور کرتے ہوئے
میرا دل پہلے سے بھی زیادہ حمد باری تعالیٰ سے لبریز ہو گیا.
Page 17
تین بنیادی تخلیقی اصول
1- تین بنیادی تخلیقی اصول
انسانی تعلقات کے تین مدارج :
ا: عدل-----کامل انصاف.۲: احسان.....کسی کو اس کے حق سے زیادہ عطا کرنا.ما
5
: ایتا عذی القربی ---- کسی کے ساتھ اپنے قریبی رشتہ داروں جیسا سلوک روا رکھنا.آج کے خطاب کیلئے میں نے جس آیت کا انتخاب کیا ہے وہ بہت ہی وسیع اور جامع مضمون پر
مشتمل ہے
إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَايْتَائِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى
عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ
(النحل 91:16)
ترجمہ: یقیناً اللہ عدل کا اور احسان کا اور اقرباء پر کی جانے والی عطا کی طرح عطا
کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی اور نا پسندیدہ باتوں اور بغاوت سے منع کرتا ہے.وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تا کہ تم عبرت حاصل کرو.اللہ تعالیٰ ہمیں صرف عدل ہی کی تعلیم نہیں دیتا بلکہ اسے آگے بڑھاتے ہوئے چاہتا ہے کہ ہم
احسان کریں اور اس مقام پر ٹھہرنے کی بجائے انسانی تعلقات میں ایتا عذی القربی کے درجے تک
پہنچیں یعنی محبت اور نگہداشت کا ایسا اظہار ہو جو ایک بچے کیلئے اس کی ماں میں دیکھا جا سکتا ہے.یاں اپنے بچے کے ساتھ بغیر کسی طمع اور لالچ کے محبت کرتی ہے.اس کے جذبات میں کسی قسم کا کوئی
تصنع نہیں بلکہ ایک طبعی بہاؤ ہوتا ہے.اپنے پیاروں کیلئے اس کے اظہار محبت میں ہمیشہ بے ساختہ پن
ہوا کرتا ہے.یہ وہ مثال ہے جو ایتاً ء ذی القربی کی روح کو خوب واضح کرتی ہے.مذکورہ بالا آیت کے پہلے حصے میں انسانی تعلقات کے تین مدارج مقرر فرما دیئے گئے
ہیں.اللہ تعالیٰ مومنوں سے کم سے کم لیکن سب سے اہم مطالبہ یہ کرتا ہے کہ وہ عدل کے مقام پر فائز
ہوں گے.لیکن وہ عدل کے مقام پر ٹھہریں گے نہیں بلکہ آگے قدم بڑھاتے ہوئے احسان کی
سرزمین میں داخل ہوں گے اور محض لوگوں کے حقوق ادا کرنے والے نہیں ہوں گے بلکہ بنی نوع
انسان کو ان کے حق سے زیادہ ادا کرنے کا سلیقہ سیکھیں گے اور ایسے لوگوں پر بھی اپنی جود وسخا کا فیض
Page 18
6
عدل، احسان اور ایتاء ذي القربى - حصه اول
عام کریں گے جو ان پر کوئی حق نہیں رکھتے.اس مضمون کو قرآنی اصطلاح میں احسان کے نام سے یاد
کیا گیا ہے.یاد رہے کہ احسان کے اصطلاحی معانی میں اور مضامین بھی شامل ہیں.جب یہ
اصطلاح بندہ اور خدا کے تعلق میں استعمال ہوتی ہے تو اسی نسبت سے اس کے معانی بدل جاتے
ہیں.جس کا ذکر آئندہ مناسب موقع پر کیا جائے گا.انشاء اللہ.تیسری اصطلاح ایتا عوذی القربی ہے، جو اس آیت کریمہ میں استعمال کی گئی ہے.اس سے
ہے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں سے لطف و احسان کا سلوک کرنا.اس لحاظ سے ہم سے یہ
توقع کی گئی ہے کہ ہم دوسروں سے احسان کا سلوک اس رنگ میں کریں کہ ہمارے اندر کسی قسم کا
احساس تفاخر پیدا نہ ہو بلکہ یہ سلوک ہم اس رنگ میں کر رہے ہوں گویا ایک فرض ادا کر رہے ہیں نہ کہ
دوسروں پر احسان.اس آیت کریمہ کے دوسرے حصے میں تین ایسی صفات بیان کی گئی ہیں جن سے مومنوں کو بچنا
چاہئے.یہ ان تین صفات کے مقابل پر ہیں جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ مومنوں میں پیدا ہوں.چنانچہ
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:
وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْى يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُونَ
(النحل91:16)
ترجمہ: اور بے حیائی اور نا پسندیدہ باتوں اور بغاوت سے منع کرتا ہے.وہ تمہیں
نصیحت کرتا ہے تا کہ تم عبرت حاصل کرو.بے حیائی ، نا پسندیدہ باتیں ، اور بغاوت اول الذکر مثبت صفات یعنی عدل، احسان اور
ایتاء ذی القربی کے مقابل پر تین منفی صفات ہیں.یہ آیت اس قدر وسیع مضامین پر حاوی ہے کہ جب میں نے آج کی تقریر کیلئے اس آیت کا
انتخاب کیا تو مجھے خیال آیا کہ اس سال صرف پہلے آدھے حصے پر کچھ کہوں گا.پھر جب میں نے غور کیا
تو ان مضامین کی گہرائی اور گیرائی نے مجھے حیرت میں ڈال دیا جن پر یہ آیت حاوی تھی.نئی نئی جہتوں
میں علم و حکمت کے ایسے ایسے مضامین کھلنے لگے کہ جن کے ہر زاویے سے علم ومعرفت کا ایک نیا جہان
دکھائی دینے لگا.پھر میں نے سوچا کہ یہ تو ممکن نہیں کہ آج کی مجلس میں آیت کا ایک حصہ بھی بیان
ہو سکے اس لئے بہتر ہوگا کہ صرف عدل سے متعلق کچھ کہوں پھر عدل کے مضمون پر غور کیا تو عدل کا
مضمون ہی اتنا وسعت پذیر ہو گیا کہ یوں لگا جیسے ساری کائنات پر محیط ہو.اور جیسا کہ میں بیان
Page 19
تین بنیادی تخلیقی اصول
7
کروں گا یہ محض کوئی دعوی نہیں بلکہ ایک ایک لفظ حقیقت پر مبنی ہے اور عدل کا مضمون جو قرآن کریم
میں بیان ہوا ہے اس قدر وسیع ہے کہ بلا شبہ ساری کائنات پر حکمران ہے.نیز یہ مضمون محض وسیع ہی
نہیں بلکہ بہت گہرا اور لطیف بھی ہے اور کائنات کے مخفی در مخفی اسرار کی طرف رہنمائی کرتا ہے.پس
خدا تعالیٰ فضل فرمائے تو آج کی اس مجلس میں جس حد تک بھی ممکن ہوا عدل کا مضمون قرآنی آیات کی
روشنی میں سمجھنے کی کوشش کی جائے گی.آج انسانیت کو اس عالمگیر نظام عدل کے اطلاق کی اشد ضرورت ہے.وہ تمام بیماریاں جو
انسانی تعلقات کو مکدر اور آلودہ کر رہی ہیں، عدل ہی کے عدم نفاذ کی پیداوار ہیں.بنی نوع انسان کو
اس کی اتنی شدید ضرورت ہے کہ اگر ہم نے قرآنی تعلیم کی روشنی میں تمام بنی نوع انسان کو عدل سے
روشناس نہ کرایا تو یہ دنیا گمراہی اور جہالت کے اندھیروں میں بھٹکتی رہے گی اور انسان ، انسان کے
ہاتھوں شدید اذیت اٹھاتا رہے گا.اس لئے یہ ہمارا انتہائی اہم فریضہ ہے کہ ہم دنیا کو عدل مطلق کے
اس قرآنی اصول سے روشناس کرائیں.قرآن کریم کی جامع ترین آیت:
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مذکورہ بالا آیت پر غور کیا تو وہ بے ساختہ
پکارا تھے کہ یہ قرآن کریم کی جامع ترین آیت ہے.حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر مفسر قرآن صحابی کا یہ تبصرہ کوئی معمولی
اہمیت کا حامل نہیں ہے بلکہ قرآن کریم پر ان کے عمر بھر کے فکر و تدبر کا
ثمرہ ہے.بالفاظ دیگر حضرت
عبد اللہ بن مسعودؓ ہماری توجہ اس حقیقت کی طرف مبذول کرواتے ہیں کہ یہ آیت قرآن کریم میں
بیان فرمودہ تمام مضامین سے تعلق رکھتی ہے.حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے علاوہ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک بھی
یہ آیت ایک خاص شان کی حامل تھی.چنانچہ جمعہ کے خطبہ ثانیہ میں اس آیت کی باقاعدہ تلاوت کا
رواج حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے شروع ہوا.اس پہلو سے حضرت عمر بن
عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بعد کے تمام مسلمانوں پر یہ ایک بہت بڑا احسان ہے.اس آیت کریمہ نے مومنوں پر جو گہرا اثر چھوڑا یہ اس کی دو ایسی مثالیں ہیں جو میں نے اپنا
نقطہ نظر مزید واضح کرنے کیلئے دی ہیں تاہم اس آیت کے اثرات مسلمانوں پر ہی دکھائی نہیں دیتے
بلکہ حضرت اقدس محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض شدید معاندین بھی اس آیت کی
Page 20
8
عدل، احسان اور ایتاء ذي القربى - حصه اول
عظمت سے حیرت انگیز طور پر متاثر دکھائی دیتے ہیں.چنانچہ بیان کیا جاتا ہے کہ قریش مکہ کے ایک
سردار ولید نے جب یہ آیت سنی تو اس نے کہا کہ :
واہ کیسی آیت ہے، کیسی رونق ہے اس کے منہ پر اور کیسی بہار ہے.“
اس آیت کے تناظر میں نظام عدل تخلیق کائنات میں ایسی وسعت اور خوبصورتی سے کارفرما
دکھائی دیتا ہے کہ جس کے اطلاق سے گویا ایک اور جہانِ معنی جنم لیتا ہے جس کے بعد اس سے بھی
بڑے درجے یعنی نظام حسن و احسان کا راستہ نکلتا ہے اور اسی نظام حسن و احسان سے ایتا عذی القربی
کی عظیم منازل کی طرف راہیں نکلتی ہیں.آیت کے مضامین کا عالم نباتات اور عالم حیوانات پر اطلاق:
تکمیل کی نچلی سطح سے لے کر اعلیٰ سطح تک نباتات اور حیوانات کی دنیا بھی عدل و احسان اور
ایتاً وذی القربیٰ کے اسی بنیادی نظام کے تابع ہے.حتی کہ انسان کی سطح تک بلند ہوتے ہوتے یہ
مضمون اور بھی زیادہ وسعت اختیار کر جاتا ہے.اس اصول کے اطلاق کے اعتبار سے
مخلوق کو تین طبقات میں تقسیم کیا جاسکتا ہے.پہلا طبقہ بے جان
مخلوق کا ہے.دوسرا طبقہ وہ ہے جس کا زمانہ زندگی کے ظہور سے لے کر انسان ، جو کہ ارتقا کی آخری
منزل ہے، کے وجود میں آنے تک ممتد ہے.اور تیسرا اور آخری درجہ صرف انسان سے تعلق رکھتا
ہے.یہ تمام گروہ ایک ہی اصول کے تابع ہیں لیکن اول الذکر دو گرو ہوں یعنی بے جان مخلوقات اور
ادنی درجے کے حیوانات میں یہ اصول ایک ایسے قانون کی شکل میں کارفرما دکھائی دیتا ہے کہ جس
میں بظاہر شعور کا کوئی کردار نظر نہیں آتا.یہ قانون کسی شعوری کوشش کے بغیر دریا کے بہاؤ کی طرح
ان کی حرکات و سکنات میں جاری وساری رہتا ہے.قوانین قدرت سے انحراف کا انہیں کچھ بھی
اختیار نہیں ہے.لیکن نسبتاً اعلیٰ درجے کے حیوانات کو جو انسان سے نچلے درجے پر ہیں دیکھیں تو
معلوم ہوتا ہے کہ وہ بے جان مخلوقات کی طرح اپنے فیصلے غیر شعوری طور پر نہیں کرتے بلکہ اپنے
وجدان کے تابع رہ کر کرتے ہیں.وجدان دراصل لاشعور اور مکمل انسانی شعور کے درمیان واقع
دکھائی دیتا ہے لیکن تمام انواع حیات میں سے صرف انسان ہی ہے جو اپنے وجدان کی پیروی کرنے
پر مجبور نہیں بلکہ اسے شعوری فیصلے کرنے کا اختیار دیا گیا ہے کہ وہ چاہے تو عدل کے رستوں پر چلے اور
چاہے تو ظلم اور نا انصافی کی راہ اپنالے.
Page 21
تین بنیادی تخلیقی اصول
توازن پیدا کرنے والے قانون کو چلانے والا رہنما اصول:
9
پس انسانی زندگی کی سطح پر عدل کے مضمون میں آزادانہ مرضی کا عنصر داخل ہو جاتا ہے.اگر
انسان خدا تعالیٰ کے دیئے ہوئے اس اختیار کو غلط استعمال کرے اور غلط رستہ اپنالے تو وہ ترقی کی
جانب سفر نہیں کر سکتا بلکہ تنزل کی ایسی راہوں پر چل پڑتا ہے جو اسے ادنیٰ سے ادنی ترین حالت کی
طرف لوٹا دیتی ہے.اس ارتقائی عمل کا ذکر مندرجہ ذیل آیات میں ملتا ہے:
لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَهُ أَسْفَلَ
سفِلِينَ ) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ
مَمْنُونٍ
(التین 5:95 تا 7 )
ترجمہ: یقیناً ہم نے انسان کو بہترین ارتقائی حالت میں پیدا کیا.پھر ہم نے
اسے نچلے درجے کی طرف لوٹنے والوں میں سب سے نیچے لوٹا دیا.سوائے ان
کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال بجالائے پس ان
کیلئے غیر منقطع اجر ہے.د
ایک جاری و ساری انعام سے مراد غیر منقطع مسلسل اخلاقی اور روحانی ارتقا ہے.”قوام“ کا
لفظی معنی بھی یہی ہے کہ ادنیٰ حالتیں اعلیٰ حالتوں میں تبدیل ہوتی ہوئی دکھائی دیں اور ایک مسلسل
ترقی کا جاری عمل نظر آرہا ہو.” المنجد میں اس کا معنی تعدیل یعنی عدل کا نفاذ بھی کیا گیا ہے.یہ آیات قرآنی حیوانی زندگی کے اس ارتقا کا ذکر کر رہی ہیں جس کا نقطۂ عروج انسان ہے نیز یہ
آیات انسان کے ذہنی اور اخلاقی ارتقا کا احاطہ بھی کر رہی ہیں.ادنیٰ درجے کی ذہانت رکھنے والے
حیوانات جیسے جیسے ارتقا کا سفر طے کرتے جاتے ہیں، وہ ذہین تر جانوروں کی شکل اختیار کرتے چلے
جاتے ہیں.یقینا خدا تعالیٰ نے عدل ہی کے ذریعے زندگی کی تخلیق کا آغاز کیا ہے اور اسی اصول عدل
کے اطلاق کے ذریعہ زندگی کا ارتقا شروع ہوا ہے جو درجہ بدرجہ اپنی آخری منزل تک پہنچا ہے.پس اس آیت کریمہ نے یہ راز کھولا کہ ارتقائی منازل کے ذریعے بالآخر انسان کی تخلیق کا
کرشمه در اصل احسن تقویم کا کرشمہ ہے.گویا ارتقا کی طرف اُٹھنے والا ہر قدم ایسا اعلیٰ اور موزوں
دکھائی دیتا ہے کہ اس سے بہتر ممکن نہ تھا.امر واقعہ یہ ہے کہ اس قرآنی اصطلاح نے اندھے ارتقا کے
نظریہ کو مسترد کر کے رکھ دیا ہے.انسانی زندگی میں جس چیز کو ہم عدل کہتے ہیں اگر اسے قانون کی
صورت میں بغیر اختیار کے مخلوقات میں جاری کیا جائے تو اسے تعدیل“ کہا جائے گا.پس اللہ تعالیٰ
Page 22
10
عدل، احسان اور ایتاء ذي القربى - حصه اول
کی مخلوقات کی ادنیٰ حالتوں سے اعلیٰ حالتوں کی طرف تمام تر ترقی تقویم اور تعدیل پر منحصر تھی.اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ارتقا کے اس سفر میں جوارب ہا ارب سال پر پھیلا پڑا ہے انسان
کیلئے کوئی اگلی منزل بھی ہے؟ کیا یہ ارتقا اپنے نقطۂ اختتام تک پہنچ گیا ہے یا ابھی تک جاری وساری
ہے؟ عقل یہ کہتی ہے کہ جب انسان نے عدل ہی کی بنا پر اتنی عظیم الشان ترقی کی ہے تو عدل سے
انحراف کے نتیجہ میں ترقی معکوس بھی ضرور ہونی چاہئے اور انسان کو درجہ بدرجہ تنزل کی طرف لوٹ جانا
چاہئے.جسمانی ساخت کے اعتبار سے تو بے شک انسان تنزل کا شکار نہیں ہو گا لیکن یہ عین ممکن ہے
کہ وہ ذہنی اور اخلاقی اور حواس خمسہ کی تکمیل کے اعتبار سے اس قدر نیچے گر جائے اور اتنا بگڑ جائے
کہ جانوروں کی مانند ہو جائے.مرتبہ ارتقا کے نقطۂ عروج تک پہنچائے جانے کے بعد انسان کو جو اختیار حاصل ہوتا ہے اس
کے متعلق دوسرا امکان یہ ہے کہ اگر وہ عقل سے کام لے اور سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے
ارتقا سے سبق سیکھے اور جان لے کہ دراصل اس کا وجو دار ہوں سال
پر محیط ارتقا کے عمل میں جاری عدل
کا ثمرہ ہے تو لاز م وہ اپنے لئے ایسا لائحہ عمل مرتب کرے گا جو ہر گز قوانین عدل سے متصادم نہ ہو.اس صورت میں ارتقا کا عمل رُکے گا نہیں بلکہ آہستہ آہستہ سہی لیکن استقلال کے ساتھ آگے بڑھتا
چلا جائے گا اور انسان کو اُس کی ادنیٰ حالتوں سے اعلیٰ حالتوں کی طرف اُٹھاتا چلا جائے گا.ارتقا کی
ان دونوں قسموں میں فرق صرف یہ ہے کہ پہلی قسم کا ارتقا بنیادی طور پر جسمانی اور ذہنی تھا جبکہ دوسری
قسم انسان کے ذہنی، اخلاقی اور روحانی ارتقا سے تعلق رکھتی ہے.ذہنی ارتقا در اصل انسان کے حواسِ
خمسہ کا ارتقا ہے.اس سورت کی اگلی آیات بعینہ اسی مضمون پر روشنی ڈال رہی ہیں اور ان سوالات کو حل کر رہی
ہیں.پس پہلا سوال قرآن کریم نے وہی اُٹھایا ہے جس پر ابھی گفتگو کی گئی ہے کہ عدل کی وجہ سے ترقی
تھی تو اُسے چھوڑنے کے نتیجے میں تنزل ہونا چاہئے.چنانچہ فرمایا: ثُمَّ رَدَدْنَهُ أَسْفَلَ سَفِلِينَ
اس آیت میں اَسْفَلَ سَفِلِينَ سے مراد انتہائی ذلیل حالت ہے.لیکن اس کا یہ مطلب ہر گز نہیں
کہ انسان
کا تنزل جسمانی طور پر اس طرح ہوگا کہ وہ زندگی کی کوئی اور شکل اختیار کر لے یعنی امیبا کی
حالت تک یا اس سے بھی کم تر.تاہم ایسے حالات میں دائمی ترقی کے راستے کی طرف رہنمائی کرنے والی امید کی ایک کرن
دکھائی دیتی ہے.وہ لوگ جو خدا تعالیٰ پر ایمان لائیں گے اور اعمال صالحہ بجالائیں گے انہیں یہ وعدہ دیا
Page 23
تین بنیادی تخلیقی اصول
11
گیا ہے کہ ان کا روحانی ارتقا ہمیشہ جاری رہے گا.یادر ہے کہ تقویٰ کی بنیا د عدل پر ہے لہذا ایسا کوئی عمل
بھی صالح قرار نہیں دیا جا سکتا جو عدل سے خالی ہو.وہ لوگ جو دائمی ترقیات کی راہوں پر چلنا چاہتے
ہیں ان سے کم از کم یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ عدل کے تقاضے پورے کریں.اگر چہ عدل کے علاوہ بھی
بعض صفات ایسی ہیں جو اگر حاصل ہو جائیں تو تقویٰ اور اعمال صالحہ کا معیار بلند ہوتا جائے گا.اس
پس منظر میں اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ کا مطلب یہ ہوگا کہ جب تک انسان عمل صالح پر قائم رہے گا
اُسے اجر سے محروم نہیں کیا جائے گا.اور اجر یہ ہوگا کہ وہ ہمیشہ اعلیٰ حالتوں کی طرف ترقی کرتا رہے گا.مضمون کا یہ حصہ تو کسی قدر واضح ہو چکا ہے لیکن اس نظریے کو تسلیم کرنے سے طبعا ایک سوال
پیدا ہوتا ہے کہ انسان کے ادنیٰ حالت کی طرف لوٹ جانے سے کیا مراد ہے؟ قرون وسطی کے بعض
مسلم مفکرین کا خیال تھا کہ انسان تنزل کا شکار ہو کر جسمانی طور پر واقعہ زندگی کی ادنیٰ حالت اختیار
کر سکتا ہے.وہ قرآن کریم کی بعض آیات کے ظاہری اور لفظی معانی لے کر یہ نتیجہ اخذ کرتے تھے کہ
انسان فی الواقع بندر ، سؤر اور گدھے میں تبدیل ہو سکتا ہے.اس سلسلے میں بہت سی عجیب و غریب کہانیاں بیان کی جاتی ہیں.مثلاً قرون وسطی کے بعض
مسلم علماء نے بعض قرآنی آیات اور احادیث کو غلط رنگ میں سمجھا اور ایک ایسے فرضی شہر کے متعلق
کہانی گھڑ لی جہاں بعض سرکش یہود کو بندر اور سور بنا دیا گیا.وہ اس شہر کا نام نہیں بتا سکتے کیونکہ تاریخ
میں ایسے کسی شہر کا کوئی ذکر نہیں ملتا نہ ہی وہ اس بات پر روشنی ڈال سکتے ہیں کہ ایسی مسخ شدہ قوم میں
توالد و تناسل کا سلسلہ کیونکر جاری رہا؟ وہ صرف یہ بتاتے ہیں کہ ایک دن صبح کے وقت یہ سب
اچانک اس طرح مر گئے کہ بے چارے ماہرین آثار قدیمہ کیلئے کوئی نشان تک نہ چھوڑا.پرانے علماء میں سے مجاہد نے اس کو ٹھیک طرح سمجھ کر بیان کیا ہے کہ خدا نے سچ مچ ان کو بندر
بن جانے کا حکم نہیں دیا تھا بلکہ جس طرح احمق اور بے شرم کو گدھا کہہ دیا جاتا ہے اسی طرح ان کو بندر
کا نام دیا گیا ہے.(1) پس اسفل سفلین کی حالت کی طرف لوٹنے کا بہر حال یہ مطلب نہیں ہو
سکتا کیونکہ جسمانی طور پر بندر اور سؤر زندگی کے سب سے نچلے طبقے سے تعلق نہیں رکھتے بلکہ ان سے
بھی ادنی اقسم کے جاندار پائے جاتے ہیں.جب ہم کہتے ہیں کہ انسان کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ چاہے تو عدل سے کام لے چاہے تو نہ لے،
تو ہرگز یہ مراد نہیں کہ اسے اس بارے میں لامحدود اختیار دیا گیا ہے.امر واقعہ یہ ہے کہ انسانی زندگی
کے بے شمار ایسے شعبے ہیں جن میں اصول عدل از خود کار فرما ہیں اور انسان کو آج بھی اختیار نہیں اور نہ
Page 24
12
عدل، احسان اور ایتاء ذي القربى - حصه اول
ہی اسے نظام میں دخل دینے اور اس کا توازن بگاڑنے پر کوئی مقدرت ہے.اس کی مزید وضاحت
ان خلیات کے ذریعے کی جاسکتی ہے جن سے تمام انواع حیات معرض وجود میں آتی ہیں.درحقیقت
ہر ایک خلیے کے اندر کسی بھی جاندار کی صفات کا حامل وسیع اور پیچیدہ نظام موجود ہے جس کے توازن
کو بگاڑنے کا انسان کو کوئی اختیار نہیں ہے.پس اَسْفَلَ سَفِلِينَ میں گرنے کے ایک اور معنی انسان
کی ذہنی صلاحیتوں میں بگاڑ کے بھی ہو سکتے ہیں.جو لوگ اپنے دماغ پر اختیار کھو بیٹھتے ہیں وہ بعض
اوقات جانوروں جیسی حرکات کرنے لگتے ہیں.یہ مماثلتیں جسمانی سے زیادہ ذہنی ہوتی ہیں اور
بے شمار ہوسکتی ہیں.پاگل شخص کتوں اور سوروں جیسی حرکات بھی کر سکتا ہے یا اس سے بھی اونی
جانوروں کی نقالی کر سکتا ہے.پس آج بھی انسانی زندگی ایک وسیع اور عظیم الشان نظام تقویم کے سہارے قائم ہے اور
انسان کی خوش نصیبی ہے کہ وہ الا ماشاء اللہ اس نظام میں دخل اندازی کا اختیار نہیں رکھتا البتہ جہاں
وہ اخلاقی حدود کو توڑتا ہے وہیں جانوروں کی مانند بلکہ اُن سے بھی بدتر ہو جاتا ہے.درحقیقت یہی
وہ دائرہ ہے جس کے متعلق ہم یقین سے کہ سکتے ہیں کہ اَسْفَلَ سَفِلِينَ کا قرآنی اصول پورے
طور پر اطلاق پاسکتا اور پاتا ہے.یہ انسان ہی تو ہے جو اپنے جیسے انسانوں کی دشمنی میں درندوں
سے بھی بڑھ جاتا ہے.پس ضروری ہے کہ ہم اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ انسان کن امور میں با اختیار ہے کیونکہ
اَسْفَلَ سَفِلِينَ کا عمل صرف اسی دائرہ میں جاری ہوگا جس میں اسے اختیار بخشا گیا.انسان سے
ادنی حیوانی حالتوں میں ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ حیوانات کا طرز عمل بڑی حد تک اپنی جبلی قوتوں
کے تابع ہوتا ہے.ان کی سوچ اور قوت فیصلہ کا ان کی روز مرہ زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا.کوئی ایسا
ضابطہ حیات ان کے سامنے نہیں ہوتا جس کو باشعور طور پر اختیار کرنا یا نہ کرنا ان کے قبضہ قدرت میں
ہو.چنانچہ ان کی زندگی کے جملہ شعبہ جات فطری قوانین کے تابع ہوتے ہیں اور وہ فطری قوانین کی
پیروی پر مجبور ہیں.اگر درندوں کو اپنی بقا کیلئے کسی خاص قسم کی غذا کی ضرورت ہے تو وہ اسے حاصل
کرنے کیلئے وہ سب کچھ کر گزریں گے جو اُن کے بس میں ہے.وہ کسی ضابطہ اخلاق کے پابند نہیں
کہ یہ خوراک اس طریق پر حاصل کر دیا اُس طریق پر اس لئے ان
کا اپنی بقا کیلئے کسی دوسرے جانور کو
مارڈالنا عدل کے منافی قرار نہیں دیا جا سکتا نہ ہی کسی موقع پر کسی جانور کی زندگی تلف نہ کرنے کو عدل
قرار دیا جا سکتا ہے.جاسکتا.
Page 25
تین بنیادی تخلیقی اصول
13
پس حیوانی زندگی میں چونکہ نہ کوئی ذمہ داری ہے اور نہ ہی ضابطہ حیات، اس لئے حیوانات
سے تعلق رکھنے والی عدل کی تعریف انسانی زندگی سے تعلق رکھنے والے شعبہ عدل کی تعریف سے کلیۂ
مختلف ہے.اسی وجہ سے اس ابتدائی حصہ میں عدل کو قوام اور تعدیل کو تقویم کا نام دیا گیا ہے تا کہ کسی
قسم کا کوئی اشتباہ نہ رہے.یاد رکھنا چاہئے کہ تقویم سے مراد وہاں توازن قائم کرنا ہے جہاں ایک جاندار توازن کی
ضرورت کے باوجود اس کی اہمیت کو شعوری طور پر سمجھنے سے قاصر ہوتا ہے.پس تقویم بہت سے
قوانین قدرت کی شکل میں ظاہر ہونے والا خدا تعالیٰ کا وہ فعل ہے جس کی وجہ سے زندگی کی ترقی کا
سفر بڑی حد تک راہ اعتدال یعنی صراط مستقیم پر قائم رہتا ہے.اس سارے سفر میں جس کا آخری مقصود انسان تھا زندگی خدا تعالیٰ کی مشیت کے مطابق تقویم
کے رستہ پر گامزن رہی تاکہ اس کا رخ اپنی منزل کی جانب ہی رہے.ارتقا کے اس طویل سفر میں
حاصل ہونے والے بین السطور نتائج ہی ہیں جو اس وقت بھی زندگی کی رہنمائی کرتے ہیں جب وہ
انسانی شکل میں ظہور پذیر ہوتی ہے.مگر اس کے بعد دیگر عوامل مثلاً ما حول، خاندان اور نسلی اثرات
انسان کو اس کے درمیانی رستہ سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں.اس مرحلہ پر ان اثرات کا مقابلہ
کرنے کی شعوری کوشش کو قرآن کریم کی اصطلاح میں ” تعدیل“ کہا گیا ہے.انسان اگر چہ اس منزل تک پہنچ چکا ہے جہاں وہ شعوری طور پر یہ آزادانہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ وہ
راہِ اعتدال پر قائم رہے یا اس سے انحراف کرلے لیکن اس کے باوجود تقویم کا عمل خاموشی سے جاری
رہتا ہے اور انسان کو شعوری طور پر اس بات
کا علم نہیں ہو پاتا کہ اس کے ساتھ کیا ہورہا ہے؟ انسان کی
خوش قسمتی یہ ہے کہ وہ اپنے اندر کار فرما عمل تقویم میں دخل نہیں دے سکتا البتہ وہ سطحی طور پر اس عمل
میں مداخلت کر سکتا ہے اور ایسا اس وقت ہوتا ہے جب وہ جانتے بوجھتے ہوئے یا حادثاتی طور پر اپنی
صحت کا خیال نہیں رکھ پاتا.یہ غفلت یا حادثہ انسان کے کسی اندرونی عضو کے چھوٹے سے حصہ کو
نقصان پہنچا کر مجموعی توازن کو بگاڑنے کا باعث بنتا ہے.اس طرح ایک چھوٹی سی بیماری بھی سارے
جسم پر اثر انداز ہو کر خرابی صحت کا موجب بن جاتی ہے.انسانی بدن میں کارفرما تمام قوانین فطرت
اس کی صحت کی حفاظت میں مصروف ہیں اور یہ سب کچھ دورانِ ارتقاء تقویم کے لمبے عمل سے
گزرنے کا نتیجہ ہے.ایک محقق کیلئے ماحولیاتی نظام (ECOSYSTEM) کا مطالعہ، عالم حیوانات میں جاری نظام عدل
Page 26
14
عدل، احسان اور ایتاء ذي القربى - حصه اول
کو سمجھنے میں مددگار ہو گا لیکن اس کی تفصیل بعد میں بیان کی جائے گی، یہاں یہ توجہ دلانا مقصود ہے کہ انسان
سے پہلے کی حیوانی زندگی کا انسان کی زندگی سے مابہ الامتیاز یہ ہے کہ انسان بہت سے ایسے امور میں
با اختیار کردیا گیا ہے جن میں ادنیٰ درجہ کے حیوانات بااختیار نہیں بنائے گئے اور یہی وہ دائرہ اختیار ہے
جہاں اُسے کچھ فوائد حاصل ہوتے ہیں اور کچھ نقصانات یعنی عدل کو اختیار کرنے کے نتیجہ میں اسے لامتناہی
ترقی کا وعدہ دیا گیا ہے اور عدل کو چھوڑنے کے نتیجہ میں اسفل سفلین کی حالت کی طرف لوٹنے سے
متنبہ کیا گیا ہے.
Page 27
تخليق كائنات
2 - تخلیق کائنات
15
اب ہم یہ جائزہ لیں گے کہ کائنات کے اجزائے ترکیبی کس طرح ان قوانین کے تحت کام کر
رہے ہیں جو مندرجہ ذیل آیات میں بیان کئے گئے ہیں:
وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ
وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ (الرحمن 8:55 (10)
ترجمہ: اور آسمان کی کیا ہی شان ہے ! اس نے اسے رفعت بخشی اور نمونہ عدل
بنایا تا کہ تم میزان میں تجاوز نہ کرو اور وزن کو انصاف کے ساتھ قائم کرو اور تول
میں کوئی کمی نہ کرو.ان آیات میں اللہ تعالیٰ آسمانوں کی بلندی کے ساتھ ساتھ وسعت کی طرف بھی اشارہ کرتے
ہوئے فرماتا ہے کہ اُس نے ان کو بہت بلند پیدا کیا ہے.یہ دونوں اوصاف یعنی بلندی اور وسعت
کلیۂ توازن پر منحصر ہیں.چنانچہ یہ وسیع تر کائنات نہ صرف یہ کہ عدل کے اصول پر بنائی گئی ہے بلکہ
عدل اس میں ایک کسوٹی کے طور پر بھی کارفرما ہے.میزان کے لفظ میں اصول و ضوابط کے ساتھ ساتھ وہ آلات بھی شامل ہیں جن سے عدل کو ماپا
جا سکتا ہے.اس کائنات میں آدمی کیلئے یہ پیغام مضمر ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے تخلیق کردہ
آسمانوں اور جو کچھ ان میں ہے، کا بنظر غائر جائزہ لے تو اس میں مکمل تو ازن ، کامل ہم آہنگی اور
مطابقت پائے گا نیز اللہ تعالیٰ کے اس وسیع تخلیقی منصوبہ پر غور کرنے سے ہی انسان عدل کے حقیقی
معانی سمجھ سکتا ہے.تمام کا ئنات ایک ہی اصول کے تابع ہے اور اس کے اجزائے ترکیبی باہم متحد ہو کر اس کی
بناوٹ اور حرکت میں ایک شاندار ہم آہنگی پیدا کرتے ہیں.کائنات میں موجود مختلف چیزوں کا
توازن اگر ذرا سا بھی بگڑ جائے تو تمام نظام کائنات درہم برہم ہو کر رہ جائے گا اسی لئے اللہ تعالیٰ
نے نظام کا ئنات کو چلانے والے تمام قوانین انسانی دسترس سے دور صرف اور صرف اپنے ہی تصرف
میں رکھے ہوئے ہیں.تخلیق کائنات میں ہر جگہ یہی بالا قانون کارفرما دکھائی دیتا ہے جس کے تحت
فطری طور پر تناسب اور توازن قائم رہتا ہے.نظام کائنات میں جہاں کہیں بھی عدل مطلق نا پید ہوگا
وہاں شدید بدنظمی پیدا ہو جائے گی.
Page 28
16
عدل، احسان اور ایتاء ذي القربى - حصه اول
عالم جمادات میں تو ازین اور ترتیب کا عدل کی صورت میں کار فرما ہونا بتارہا ہے کہ یہ
کہ یہ کائنات نہ
صرف ایک خالق کے ہاتھ کی تخلیق ہے بلکہ وہی واحد ہستی ہے جو اس عظیم الشان کارخانہ کومسلسل قائم
بھی رکھے ہوئے ہے.اس نکتہ کو کسی آرٹسٹ کے کام کے بغور مشاہدے سے مزید کھولا جاسکتا ہے.جس کے تیار کردہ شاہ کا ر کو دیکھ کر اس کے فن اور مہارت کی عظمت کا بآسانی اندازہ کیا جاسکتا ہے.نظام کائنات کے گہرے مطالعہ سے اس حیرت انگیز حقیقت کا انکشاف بھی ہوتا ہے کہ لامحدود
اور وسیع تر ہونے کے باوجود کائنات میں کارفرما قوانین قدرت اور ان کے تابع تخلیقی عمل کے مابین
ذرہ بھر بھی تضاد دکھائی نہیں دیتا.یہ کامل ہم آہنگی اور مطابقت لازماً ایسے خدا کا پتہ دیتی ہے جو اعلیٰ،
خالق کامل اور واحد و یگانہ ہے.تا ہم سطحی نظر سے دیکھنے والوں کو کائنات میں بظاہر تضاد اور بے ہنگم
پن بھی دکھائی دیتا ہے.یوں لگتا ہے کہ جیسے اشیاء کے مقاصد اور محرکات باہم متصادم ہیں.لیکن کبھی
ختم نہ ہونے والے اس باہمی تضاد کے پیچھے عدل کا ایک پوشیدہ ہاتھ مسلسل کارفرما ہے.مختلف اشیاء
کی باہمی ترتیب اور تناسب میں ایک انتہائی خوبصورت اور حیرت انگیز توازن رکھ دیا گیا ہے اور جب
اس کا اطلاق مختلف انواع حیات کے مابین پائی جانے والی جہد للبقاء پر کیا جاتا ہے تو اسے ماحولیاتی
نظام (ECOSYSTEM) کا نام دیا جاتا ہے.تخلیق کے اس وسیع منصوبہ میں حیوانی زندگی کا بھی ایک مخصوص دائرہ کار یا مقصد ہے.ساری
کائنات میں کارفرما قوانین کو جو ایک دوسرے سے مکمل ہم آہنگ ہیں نسبتاً چھوٹے دائروں میں بھی
جاری کیا گیا ہے جو نظام زندگی کو چلاتے ہیں.در حقیقت کائنات کا ہر ایک جزو اپنے دائرہ میں ان
معین قوانین کے تابع چل رہا ہے جو بطور خاص اسی دائرہ کیلئے وضع کئے گئے تھے.کیمیا، فزکس اور
نیوکلیس میں جاری قوانین اور ان
کا باہمی عمل عالم حیوانات
کی تخلیق کا باعث ہے.حیوانات کے
وجود میں آتے ہی ایک نیا ضابطہ حیات پیدا ہوتا ہے اور پھر تمام انواع حیات کیلئے ان کے اپنے
اپنے دائروں کے ساتھ مخصوص قوانین دکھائی دیتے ہیں جن کے تابع حیات رواں دواں ہوتی ہے.اگر ہمارا یہ مطالعہ درست ہے تو پھر ہم لازماً اس نتیجہ پر پہنچیں گے کہ تخلیق کے ہر مرحلہ پر جیسے
جیسے اس کا قدم ترقی کی جانب بڑھا ہے اگر خالق اول کے علاوہ کوئی اور بیرونی طاقت بھی اس میں
دخل انداز ہوتی تو یقیناً ایک ہنگامہ اور فساد برپا ہو جاتا جس سے ساری کائنات میں ایک زلزلہ آ جاتا.یہ توازن اگر ایک مرتبہ بگڑ جائے تو کبھی بھی دوبارہ قائم یا بحال نہیں کیا جاسکتا.کائنات میں پائی
جانے والی کامل ہم آہنگی اور ترتیب کے متعلق قرآن کریم کا بعینہ یہی بیان ہے.چنانچہ مندرجہ ذیل
آیت اسی مضمون کو بڑی فصاحت و بلاغت سے بیان کر رہی ہے:.
Page 29
تخليق كائنات
ج
لَوْ كَانَ فِيْهِمَا أَلِهَةٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَ تَا فَسَبِّحْنَ اللهِ رَبِّ
الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ.(الانبیاء 23:21)
17
ترجمہ: اگر ان دونوں میں اللہ کے سوا کوئی معبود ہوتے تو دونوں تباہ ہو جاتے.پس پاک ہے اللہ عرش کا رب اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں.اس وسیع کائنات میں دوئی کا کوئی چھوٹا سا نشان بھی کہیں دکھائی نہیں دیتا.ایک دائرہ میں تمام
اشیاء باہمی طور پر بھی اور کائنات کے دیگر دائروں کے ساتھ بھی کامل ہم آہنگی کے ساتھ چلتی چلی جارہی
ہیں.کائنات میں ہر جگہ پائی جانے والی اس کامل ہم آہنگی کے بغیر ہم ارتقا
کے اس دائمی سفر کا تصور بھی
نہیں کر سکتے تھے.ایک سے زیادہ خالق ہونے کی صورت میں ایک سے زائد قوانین اس کائنات کے
حاکم ہونے چاہئیں تھے اور لازم تھا کہ ہر ایک خدا اپنے قوانین کے مطابق کائنات تخلیق کرتا جس کا
لازمی نتیجہ بے ترتیبی اور ابتری کی صورت میں نکلتا اور تمام کا ئنات ٹکڑے ٹکڑے ہو کر رہ جاتی.یہ بھی یادرکھنا چاہئے کہ کائنات میں موجود ہر ایک چیز مسلسل تغیر پذیر ہے.اگر یہ تبدیلی بہتری
کی جانب ہو تو ہم اسے ارتقا کہتے ہیں.اکثر و بیشتر کسی چیز کی حالت بہتر ہونے سے مراد اس کے
اجزائے ترکیبی کی از سر نو تنظیم و ترتیب ہوتی ہے جس سے اس کے معیار اور حسن و جمال میں اضافہ
ہوتا ہے.مختصر یہ کہ بے ترتیبی اور بدنظمی بدصورتی ہے اور ترتیب و تنظیم خوبصورتی.ارتقا کی بعینہ یہی
نوعیت ہے جس کا ہم زمین پر مشاہدہ کرتے ہیں.زندگی بتدریج پیچیدہ سے پیچیدہ تر ہوتی چلی جاتی
ہے.چنانچہ ارتقا کے ہر اگلے مرحلہ پر اس کے اجزائے ترکیبی زیادہ منظم اور مرتب دکھائی دیتے ہیں.اس تناظر میں ہم مختصر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ارتقا در اصل بدنظمی سے نظم وضبط اور کم تر نظم وضبط سے ہمیشہ
بہتر نظم و ضبط کی طرف جاری سفر ہے.در حقیقت یہی چیز زندگی اور موت کے مابین ما بہ الامتیاز
ہے.اگر چہ یہ ایک مشکل سائنسی مضمون ہے لیکن اردو کے ایک شاعر بی نارائن چکبست نے اسے
بڑے خوبصورت اور سادہ الفاظ میں یوں بیان کیا ہے:
زندگی کیا ہے عناصر کا ظہور ترتیب
موت کیا ہے انہی اجزا کا پریشاں ہونا
یعنی زندگی عناصر کی تنظیم کے سوا کچھ بھی نہیں اور موت انہی عناصر کی بے ترتیبی کا نام ہے.جب مادہ ایک مسلسل کیمیاوی عمل میں سے گزرتا ہے تو اس سے نئے اور زیادہ پیچیدہ سالماتی
مرکبات پیدا ہوتے ہیں جو بالآخر اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں جہاں بہت ترقی یافتہ اور پیچیدہ
Page 30
18
عدل، احسان اور ایتاء ذي القربى - حصه اول
نامیاتی مرکبات کی مدد سے زندگی کی پہلی اینٹ کی تشکیل ممکن ہو جاتی ہے جسے DNA کہا جاتا
ہے.زندگی کے اجزائے ترکیبی کی نئی سے نئی طرز پر تنظیم سے یہ تمام اجزائے حیات نئی سے نئی شکلیں
اختیار کرتے چلے جاتے ہیں.یہ عناصر اتنی خوبصورتی کے ساتھ باہم مربوط ہیں جیسے کسی زیور میں
ہیرے جڑے ہوئے ہوتے ہیں.جب ان عناصر میں زندگی کی آب و تاب جلوہ گر ہوتی ہے تو حیات
جگمگا اٹھتی ہے.ان عناصر کی ترتیب و تنظیم تو ڑ ڈالیں تو کچھ بھی باقی نہیں رہتا، بالکل ویسے ہی جیسے
ہیروں کو ان
کی ابتدائی کیمیائی حالت میں لے جائیں تو محض کاربن کے کچھ ٹکڑے ہی بیچتے ہیں.چنانچہ قرآن کریم یہ نتیجہ نکالنے میں بالکل حق بجانب ہے کہ اگر اس کا ئنات کے ایک سے زائد
مالک ہوتے تو ان میں سے ہر کوئی اپنے مالکانہ حقوق کیلئے دوسرے سے لڑ پڑتا ، جس کے نتیجہ میں یہ
کا ئنات بدنظمی اور ابتری کا شکار ہوکر درہم برہم ہو جاتی.بالفاظ دیگر زندگی کو ہم توازن اور ہم آہنگی کا
نتیجہ قرار دے سکتے ہیں جبکہ ان کی عدم موجودگی کا نتیجہ موت ہے.پس اگر بنی نوع انسان گہرے
معانی پر مشتمل اس قرآنی پیغام کو سمجھ کر اور تسلیم کر کے توحید سے وابستہ ہو جاتے تو آج دنیا کا نقشہ ہی
کچھ اور ہوتا.کشش ثقل کا عالمگیر قانون :
اس دعوے کے ثبوت میں کہ تخلیق کائنات میں عدل بہت اہم کردار ادا کرتا ہے
بہت سے سائنسی شواہد موجود ہیں لیکن یہاں زیر بحث امر کی وضاحت کشش ثقل کے عالمگیر
قانون کے حوالے سے ہی کافی ہوگی.اس قانون کے مطابق کا ئنات میں کوئی سے دو مادی اجسام
کے مابین ایک ایسی قوت کشش پائی جاتی ہے جو ان دونوں اجسام میں پائے جانے والے مادے
کے حاصل ضرب کے راست متناسب اور ان کے باہمی فاصلہ کے مربع کے بالعکس متناسب ہوتی
ہے.اسی باہمی کشش کو کششِ ثقل کہا جاتا ہے.ان مخالف قوتوں کے مابین کامل توازن اور
مساوات کے بغیر کائنات کا توازن برقرار نہیں رہ سکتا.یہ قانون سالموں اور ابیٹوں کے عالم صغیر پر
بھی اُسی طرح اطلاق پاتا ہے جس طرح عالم کبیر پر.ہر چیز جو مدار میں گردش کر رہی ہے اس کا اپنے مدار میں رہنا دراصل مرکز مائل اور مرکز گریز
قوتوں کے مابین مکمل توازن کا نتیجہ ہے.ایسی قوتوں پر مشتمل ایک بہت پیچیدہ جال نے اجرام فلکی کو
باہم مربوط کر رکھا ہے جس کے باعث کائنات کو ثبات حاصل ہے.قرآن کریم جب اجرام فلکی کے بیضوی مداروں میں متحرک رہنے کا ذکر فرماتا ہے تو دراصل
Page 31
تخليق كائنات
19
خدا تعالیٰ کے انہی تخلیقی کمالات کی طرف ہمیں متوجہ کرتا ہے.یہ قانون تمام نظام ہائے شمسی، کہکشاؤں
اور کہکشاؤں کے مختلف جھرمٹوں پر یکساں اطلاق پاتا ہے.حتی کہ کائنات کا چھوٹے سے چھوٹا ذرہ بھی
اس قانون کے دائرہ سے باہر نہیں.سالموں اور ایٹموں کی چھوٹی سی دنیا میں بھی ہمیں یہی دکھائی دیتا
ہے کہ ذرات اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں.کسی بھی سیارے کی اپنے مدار میں گردش کا کشش ثقل کی مخالف قوتوں کے ساتھ مکمل طور پر
متوازن ہونا ضروری ہے جو اس سیارہ کو اندر کی طرف کھینچ رہی ہوتی ہیں.اس کا انحصار سیارہ کی اس
معین رفتار پر ہے جس کے ساتھ وہ مرکز کے گرد گھوم رہا ہوتا ہے.اس رفتار کو کچھ کم کر دینے یاذ راسا
بڑھا دینے سے یہ اجرام یا تو اپنے مدار سے نکل کر منتشر ہو جائیں گے یا پھر ایک دوسرے سے ٹکرا کر
ایک دوسرے ہی میں ھنس جائیں گے.کائنات میں ایسی کامل ہم آہنگی اور مطابقت رکھنے والی
قوتوں کی صرف یہی چند ایک مثالیں نہیں ہیں بلکہ ارب ہا ارب نظام ہائے شمسی ہیں جن میں مدار
ایک حیرت انگیز معین حساب کے مطابق بنائے گئے ہیں.تاہم ایک عام آدمی کو سمجھانے کیلئے کہا
جاسکتا ہے کہ ان کا ئناتوں اور کہکشاؤں کا شمار ممکن نہیں.اس حیرت انگیز توازن کو قرآنی اصطلاح میں ” میزان کہا گیا ہے.بہت سے علماء نے اس
مضمون پر مختلف جہات سے روشنی ڈالی ہے کیونکہ کائنات کے متعلق
جستجو کا یہ سفر کبھی ختم نہیں
ہوسکتا.سائنس دان ابھی تک کا ئنات کے ان اسرار کا بھی پوری طرح احاطہ نہیں کر سکے جو بالکل سطحی
ہیں.کئی دانشوروں نے اس موضوع پر روشنی ڈالی اور مختلف زاویہ ہائے نگاہ سے بہت کچھ لکھا بھی
ہے لیکن ہرا گلا قدم اس کا ئنات میں موجود اشیاء کے وسیع تر توازن کے نئے نئے پہلو اجاگر کرتا چلا
جا رہا ہے اور اس میدان میں ہونے والی ہر نئی تحقیق قرآن کریم کے بیان فرمودہ ایک ہی لفظ کی بار بار
تصدیق کرتی چلی جارہی ہے کہ اس ساری کائنات کو چلانے والا مرکزی اصول دراصل ” میزان ہی
ہے جس کے معنی ہیں ” کامل توازن یا مطلق عدل“.آئن سٹائن نے بھی ان قوانین کے مطالعہ کے دوران جن پر اجرام فلکی کی حرکت کا دارو مدار
ہے اس موضوع پر بہت غور و خوض کیا.چنانچہ وہ کائنات میں موجود کامل ترتیب اور مکمل توازن کو دیکھ
کر ورطہ حیرت میں ڈوب گیا اور پکار اُٹھا کہ یہ حسین تو ازن ہمیں ایک ایسی بالا ہستی پر ایمان لانے پر
مجبور کرتا ہے جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا ہے.وہ شاید کسی ایسے خدا کو تسلیم نہیں کرتا تھا جو انسان
کے ساتھ ہمکلام ہو سکتا اور کوئی مذہبی تعلیم الہام کر سکتا ہے.لیکن کم از کم اسے ایک ایسے عظیم خالق
Page 32
20
عدل، احسان اور ایتاء ذي القربى - حصه اول
کے وجود کو تسلیم کرنا پڑا جو باشعور اور مدبر بالا رادہ بھی ہے اور اپنی منشاء کے مطابق کام کرنے کی
صلاحیت اور طاقت بھی رکھتا ہے.(2)
مندرجہ ذیل آیات قرآنیہ اللہ تعالیٰ کی کائنات کے عجائبات کی بھر پور وضاحت کر رہی ہیں:
تَبْرَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ الَّذِى
خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَوةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ
الْغَفُورُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمُوتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ
مِنْ تَفْوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورِ (الملک 2:67 4)
ترجمہ: بس ایک وہی برکت والا ثابت ہوا جس کے قبضہ قدرت میں تمام
بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر جسے وہ چاہے دائمی قدرت رکھتا ہے.وہی جس
نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تا کہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل کے
اعتبار سے بہترین ہے اور وہ کامل غلبہ والا اور بہت بخشنے والا ہے.وہی جس
نے سات آسمانوں کو طبقہ در طبقہ پیدا کیا.تو رحمان کی تخلیق میں کوئی تضاد نہیں
دیکھتا پس نظر دوڑا کیا تو کوئی رخنہ دیکھ سکتا ہے؟
اللہ ہی ہے جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا اور ان دونوں کے مابین ایک مسلسل جد و جہد کا
عمل جاری کر دیا ہے.یہ آیات قرآنیہ دراصل بقائے اصلح کے قانون کی وضاحت کر رہی ہیں.اسی جدوجہد کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ فرماتا ہے کہ اس کی مخلوقات میں سے کون عمل کے اعتبار سے
بہترین ہے.حق و باطل کی باہمی کشمکش کے بارے میں یہ آیات بتا رہی ہیں کہ فتح بہر حال حق کی
ہونی چاہئے اور باطل کو نیست و نابود ہو جانا چاہئے.تعمل ارتقا کا تقابلی جائزہ لینے پر یہ واضح ہوتا ہے کہ جہت یہ فیصلہ کرے گی کہ کسی چیز کا سفر
موت کی طرف ہے یا زندگی کی طرف.اگر کوئی چیز موت کی طرف بڑھ رہی ہے تو اس میں قوت حیات
مسلسل انحطاط پذیر ہوتی چلی جائے گی اور اس کا برعکس بھی یہی ہے.ان دونوں مخالف
انتہاؤں کے درمیان زندگی اور موت کے لاتعداد مدارج ہیں.کائنات میں ہر ذی روح انہی
دو سمتوں میں محو سفر ہے یعنی یا تو وہ ترقی پذیر ہے یا انحطاط کا شکار.جہاں بھی زندگی شعور کے نسبتاً
اعلیٰ مقام کی طرف بڑھ رہی ہے وہ انسانی حالت ہی کی طرف محو سفر دکھائی دیتی ہے.ادنی درجہ کی
Page 33
تخليق كائنات
21
انواع حیات کا اعلیٰ درجہ کی انواع سے موازنہ کیا جائے تو اول الذکر موت کے قریب تر دکھائی دیتی
ہیں.زندگی کی طرف اُٹھنے والا ہر ایک قدم در اصل کمال اور خوبصورتی کی طرف ہی اٹھ رہا ہے.موت کی جانب سفر کی اگر چہ ایک آخری حد ہے لیکن زندگی کے سفر میں آخری منزل کوئی نہیں ہے
کیونکہ یہ وہ سفر ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف لے جاتا ہے اور خدا کی ہستی لا محدود ہے.مندرجہ بالا دو
آیات میں اللہ تعالیٰ کی دو صفات عزیز اور غفور بیان ہوئی ہیں.عزیز کا معنی ہے کہ وہ اپنے غالب علم
کی بدولت کامل غلبہ رکھنے والا اور عزت کا سب سے بڑھ کر مستحق ہے اور غفور سے مراد ہے کہ وہ بہت
زیادہ بخشنے والا وجود ہے.یہ صفات بتاتی ہیں کہ جس وجود کے پاس جتنا زیادہ علم ہوتا ہے وہ اتنازیادہ
قابل عزت اور طاقتور ہوتا چلا جاتا ہے.دوسری صفت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اگر چہ ترقی
کے سفر کے دوران بہت سی غلطیاں سرزد ہوں گی لیکن اللہ تعالیٰ ان میں سے اکثر قصور معاف کر دے
گا اور ان کی وجہ سے انسان کو کوئی نقصان نہیں اُٹھانا پڑے گا.خدا تعالیٰ ہی ہے جس نے بہترین توازن کے ساتھ سات آسمان تخلیق فرمائے ہیں.اس کی
تخلیق میں معمولی سا بھی کوئی رخنہ یا تضاد نہیں ہے.ہمیں کائنات پر نظر دوڑا کر اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں
کوئی رخنہ تلاش کرنے کا چیلنج دیا گیا ہے.حیرت کی بات تو یہ ہے کہ بنی نوع انسان کو یہ چیلنج حضرت
اقدس محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ اس وقت دیا گیا جبکہ زمین اور آسمان کے بارہ میں لوگوں
کا علم بالکل بچگانہ اور قدیم فلسفہ پر مبنی تھا اور اس دور کے تصور کائنات میں کوئی ایسی بات نہیں تھی جس
کی بناء پر کوئی شخص اس کی خوبصورتی اور موزونیت کے دفاع میں ایسا چیلنج پیش کرنے کا سوچ بھی
سکتا.اس وسیع کائنات میں کوئی رخنہ تلاش کرنے کا یہ چیلنج ایک بار پھر دہرایا گیا ہے اور قرآن کریم
خود ہی اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ انسان اس میں ہرگز کوئی رخنہ تلاش نہیں کر پائے گا اور
اس کی نظریں تھک ہار کر اور ناکام ہو کر لوٹ آئیں گی.
Page 34
22
عدل، احسان اور ایتاء ذي القربى - حصه اول
3- زمین کا ماحولیاتی نظام
زمین اور اجرام فلکی کے مابین توازن :
زمین اور اجرام فلکی کے درمیان موجود کرہ ہوائی کا کردار بے حد حیران کن ہے.حضرت
اقدس محمد مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم پر چودہ سو سال پہلے نازل ہونے والے قرآن کریم میں اس پیچیدہ
سائنسی مشاہدات کے بارے میں پڑھ کر انسان ورطہ حیرت میں ڈوب جاتا ہے.آج کے
سائنسدانوں نے کائنات کے سربستہ راز کھولنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی ، اس کے باوجود
قرآن کریم فطرت کے قوانین اور ان کے مظاہر کے گہرے عرفان کے اعتبار سے ان سے کہیں آگے
ہے.سائنسدانوں کی کوششوں کے ثمرات قابل تعریف ہیں لیکن وہ اپنی حدود سے آگے نہیں نکل سکتے.زمین کا ہوائی کررہ:
قرآن کریم فرماتا ہے:
فَقَضْهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءِ
أمْرَهَا وَزَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ
الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (لم السجدة 13:41)
ترجمہ: پس اس نے ان کو دو زمانوں میں سات آسمانوں کی صورت میں تقسیم کر
دیا اور ہر آسمان کے قوانین اس میں وحی کئے اور ہم نے دنیا کے آسمان کو
چراغوں اور حفاظت کے سامانوں کے ساتھ مزین کیا.یہ کامل غلبہ والے
( اور ) صاحب علم کی تقدیر ہے.اللہ تعالیٰ نے آسمانوں
کی تخلیق مکمل فرمائی اور ان میں سے ہر ایک اپنی تخلیق کے مقصد کے عین
مطابق کام کر رہا ہے.پھر قرآن کریم سب سے نچلے کرہ ہوائی کو زمین سے قریب ترین آسمان قرار
دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ یہ آسمان زمین کی حفاظت کیلئے پیدا کیا گیا ہے.اُس زمانے کا انسان زیادہ
سے زیادہ یہ سمجھ سکتا تھا کہ کسی نہ کسی طرح آسمان اس کی حفاظت کر رہا ہے لیکن کسی کے وہم و گمان میں
بھی نہ تھا کہ کس چیز سے اور کیونکر اس کی حفاظت کی جارہی ہے؟
عدل کی ایک تعریف یہ ہے کہ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیا جائے نیز یہ مشاہدہ اچھی طرح کر لیا
Page 35
زمین کا ماحولیاتی نظام
23
جائے کہ کامل عدل کسی ایک جزو کو دوسرے کسی بھی جزو کے کام میں دخل اندازی کی اجازت نہیں
دیتا.جہاں تک مضر اثرات کا تعلق ہے تو اس نظام کے تمام اجزاء کو ان کے منفی اثرات سے مکمل طور
پر محفوظ بنایا گیا ہے جبکہ اس نظام کے فوائد کو دوسرے اجزاء تک پہنچنے سے نہیں روکا گیا بلکہ ان کی زیادہ
سے زیادہ فراہمی کوممکن بنادیا گیا ہے.یادر ہے کہ یہ عدل کے تصور کے منافی نہیں ہے.یہ بات سمجھ
لینے کے بعد اب ہم اس امر کا جائزہ لیتے ہیں کہ عدل جسے مادی دنیا پر اطلاق کی صورت میں کامل
توازن اور ہم آہنگی سے تعبیر کیا جاتا ہے اس کے نفاذ میں زمین سے قریب ترین آسمان کا کردار کیا
ہے؟ یہاں جب ہم عدل کا مادی دنیا پر اطلاق کرتے ہیں تو اسے کامل تو ازن اور ہم آہنگی سے ہی تعبیر
کرتے ہیں.آیئے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کرہ ہوائی کی مختلف نہیں زمین کے گرد کیا کر دار ادا کر رہی ہیں؟
یادر ہے کہ اگر چہ یہ قریب ترین آسمان بظاہر ایک ہی دکھائی دیتا ہے لیکن دراصل یہ کئی کروں میں منہ
ہے.اب ہم اس کی مختلف تہوں کے حوالے سے کچھ مزید جائزہ لیتے ہیں.زیریں کرہ ہوائی: (The Troposphere)
زمین کے قریب ترین ہوائی کرہ کو TROPOSPHERE کا نام دیا گیا ہے.یہ کرہ ہوائی
سطح زمین سے لے کر قریباً سات میل کی بلندی تک چلا گیا ہے.بلندی کے ساتھ ساتھ اس کا
درجہ حرارت بھی گرتا چلا جاتا ہے.چونکہ یہ کرہ ہوائی سطح زمین کے عین اوپر واقع ہے اس لئے ہمارا
پہلا اور براہ راست تعلق اسی کے ساتھ ہے.گیسوں کی اس سات میل موٹی تہہ نے سطح زمین کو
پوری طرح گھیر رکھا ہے اور یہ کشش ثقل کے باعث قائم ہے.اس کے کئی ایک مقاصد ہیں.تمام
نظامِ حیات نچلے آسمان کے اسی حصہ کے سہارے قائم ہے.مزید برآں یہ تہ حفاظتی حصار کا کام بھی
دیتی ہے.ان گیسوں میں ٹھوس مادہ کے بے شمار نامیاتی اور غیر نامیاتی ذرات معلق ہوتے ہیں جو ہوا
کی مسلسل حرکت کے باعث سطح ارض سے اور پر فضا میں بلند رہتے ہیں.کرہ ہوائی کا یہ حصہ زمین اور
اس پر موجود زندگی کو شہب ثاقب وغیرہ کی مسلسل بوچھاڑ سے محفوظ رکھتا ہے.اس کے بغیر زمین پر
کسی قسم کی زندگی کی بقا ممکن نہیں.ایک بات اور بھی قابل غور ہے کہ اس تہ کی کثافت اور حجم ضرورت
کے عین مطابق ہے.اگر یہ توازن خدا نخواستہ بگڑ جائے تو یہ تبہ زمین پر موجودز ندگی کیلئے نہ صرف بے سود بلکہ نقصان
کا موجب ہوگی کیونکہ اس طرح سورج کی روشنی اور دیگر مفید شعاعیں زمین تک نہ پہنچ پائیں گی.(3)
Page 36
24
عدل، احسان اور ایتاء ذي القربى - حصه اول
بالا ئی کرہ ہوائی: (The Stratosphere)
بالا ئی کرہ ہوائی کی تعریف کیلئے ولیم وین ڈر نجل (William Van Der Bijl) کا ایک
اقتباس ذیل میں درج کیا جاتا ہے:
وو
چار ہوائی کروں میں سے نیچے سے دوسری تہ Stratosphere یعنی بالائی
کرہ ہوائی ہے جس کے نچلے کنارہ کو Tropopause کہتے ہیں اور اوپر
والے کنارہ کو Stratopause کہتے ہیں.Tropopause میں عموداً
حرکت کریں تو درجہ حرارت اور موسم میں تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں جبکہ بالائی
کرہ ہوائی میں موسم تبدیل نہیں ہوتا بلکہ جیسے جیسے اوپر جاتے جائیں
درجہ حرارت بڑھتا چلا جاتا ہے.بالائی کرہ ہوائی میں ہوا کی حرکت بڑی حد
تک افقی ہوتی ہے.بالائے بنفشی شعاعوں کے اوزون میں انجذاب کے
باعث بالا ئی کرہ ہوائی کا درجہ حرارت بلند ہوتا ہے جو کہ بالعموم سطح ارض سے
(4)،،
اوپر 48 تا 53 کلومیٹر یا 30 تا 33 میل کے مابین ہوتا ہے.4
یہ دو ہوائی کرے جو ورلے آسمان کا حصہ ہیں کئی پیچیدہ کام سرانجام دیتے ہیں جن میں سے محض
چند ایک کا ذکر کیا گیا ہے لیکن یہ ابتدائی علم بھی انسان کو ورطہ حیرت میں ڈالنے کیلئے کافی ہے.اس
ور لے آسمان کو کس عمدگی سے بنا کر معین افعال سرانجام دینے کیلئے دو کروں میں تقسیم کر دیا گیا ہے.اس توازن میں معمولی سا بگاڑ بھی پیدا ہو جائے تو کرہ ارض پر زندگی قائم نہیں رہ سکتی.اوزون کی تہ میں
کسی قسم کی کمی تمام انواع حیات کو تباہ کرنے کیلئے کافی ہوگی کیونکہ اس طرح تیز کا سمک شعاعیں بلا
روک ٹوک زمین تک آ پہنچیں گی.اس مطالعہ سے نہ صرف عدل اور توازن کے گہرے معانی سمجھ میں
آتے ہیں بلکہ اس سے مخلوق اور خالق کا باہمی رشتہ بھی استوار ہوتا ہے.انسان رموز فطرت پر جس قدر
گہرا غور کرتا چلا جاتا ہے اس قدر شکر کے جذبات بڑھتے چلے جاتے ہیں نیز اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ
خدا تعالیٰ نے انسان
کیلئے کیا کچھ کر رکھا ہے ورنہ محض اتفاقات کا کوئی سلسلہ زمین پر زندگی کو پیدا اور
قائم نہیں رکھ سکتا نہ ہی زندگی کا یہ سفر اتفاقات کے سہارے آگے بڑھ کر انسان کی حاصل کردہ رفعتوں کو
پاسکتا ہے.مختلف قوتوں کے مابین توازن برقرار رکھنے کیلئے اربوں ایسے اقدامات کئے گئے ہیں جن
کے باعث یہ کرہ ارض زندگی کے قیام کیلئے ایک موزوں جگہ بن پایا ہے.
Page 37
زمین کا ماحولیاتی نظام
مقناطیسی کرہ ہوائی: (The Magnatosphere)
25
یہ کرہ ہوائی کا وہ حصہ ہے جہاں آیونائزیشن (Ionization) کے باعث پیدا ہونے والا
مقناطیسی عمل اور موصلیت، چارج شدہ ذرات کے خواص کا تعین کرنے کیلئے ضروری ہوتے ہیں.اس
کا کام بے انتہا فلکیاتی توانائی کو جذب کرنا اور اس کے بیشتر حصہ کوزمین پر پہنچنے سے روکنا ہے.فلکیاتی (cosmic) شعاعیں بنیادی طور پر دو قسم کی ہوتی ہیں ایک ابتدائی اور دوسری ثانوی.ابتدائی شعاعوں
کا بڑا حصہ پروٹونز یعنی ہائیڈ روجن کے نیوکلیس اور الفاذرات یعنی بیلیم کے نیوکلیس
پر مشتمل ہوتا ہے.ان ابتدائی شعاعوں میں سے اکثر قریباً ایک کھرب الیکٹران وولٹ توانائی کی
حامل ہوتی ہیں.اگر چہ ان میں کچھ شعاعیں سورج سے بھی نکلتی ہیں لیکن ان کی اکثریت کے ماخذ
زمین سے بہت دور ہیں.ممکن ہے کہ سپرنووا یعنی وہ ستارے جہاں بڑے بڑے دھماکے ہورہے
ہیں، ان کا ماخذ ہوں.اسی طرح ممکن ہے کہ سب سے زیادہ توانائی کی حامل شعاعیں ہماری کہکشاں
کے باہر سے آ رہی ہوں.کچھ ابتدائی فلکیاتی شعاعیں زمین کے کرہ ہوائی میں داخل ہو کر جب
آکسیجن اور نائٹروجن کے نیوکلیس کے ساتھ ٹکراتی ہیں تو ثانوی فلکیاتی شعاعوں کا باعث بنتی ہیں.یہ ثانوی فلکیاتی شعاعیں ایٹم کے چھوٹے چھوٹے ذرات یعنی الیکٹران ، پوزیٹرون، میسنز ، نیوٹرون
اور فوٹون پر مشتمل ہوتی ہیں.توانائی سے بھر پور یہ ثانوی شعاعیں کرہ ہوائی میں موجود دیگر نیوکلیس
کے ساتھ تعامل کے ذریعہ مزید ثانوی فلکیاتی شعاعیں پیدا کرتی ہیں.یکے بعد دیگرے ایسے مسلسل
ٹکراؤ کے نتیجہ میں یہ شعاعیں تعداد میں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں جسے اصطلاحاً شعاعوں کی
آبشار“ کہا جاتا ہے.فلکیاتی شعاعوں کی طرف سائنسدانوں کی توجہ اصل میں اس لئے مبذول ہوتی تھی کہ قدرت کا
یہ مظہر ان کی عقلوں کیلئے ایک چیلنج کی حیثیت رکھتا تھا.ان شعاعوں کی اہمیت اس لئے بھی بڑھ جاتی
ہے کہ یہ زمین پر زندگی کی بقا کیلئے قائم نظام پر کئی طرح سے اثر انداز ہوتی ہیں.درحقیقت انسانی
زندگی کا دارو مدار بڑی حد تک ثانوی فلکیاتی شعاعوں پر ہے.پودوں میں کلوروفل بنانے میں یہ
بنیادی کردار ادا کرتی ہیں.کلوروفل وہ مادہ ہے جو پودوں کو سبز رنگ عطا کرتا ہے.ضیائی تالیف میں
بھی ان شعاعوں کا کردار بنیادی اہمیت کا حامل ہے.یہ وہ عمل ہے جس کے ذریعے کاربن، آکسیجن
اور ہائیڈ روجن جیسے عناصر کو نامیاتی مادوں میں تبدیل کیا جاتا ہے جن سے آگے پھر نباتات کی تمام
شکلیں ظہور پذیر ہوتی ہیں.جڑوں سے لے کر پتوں ، پھولوں اور پھلوں کی ڈنڈیوں تک سب کچھ
Page 38
26
عدل، احسان اور ایتاء ذي القربى - حصه اول
اسی کلوروفل کا ہی مرہونِ منت ہے جو شمسی اور ثانوی شعاعوں
کی مجموعی توانائی کے ذریعہ چلنے والے
ایک کارخانے کی طرح مصروف عمل ہے.یہ ثانوی فلکیاتی شعاعیں اس قدر لطیف ہوتی ہیں کہ بہت موٹے سیسے کے بھی آر پار ہو جاتی
ہیں.بے حد گہری کانوں اور سمندروں کی تہوں میں بھی ان کی موجودگی کا پتہ چلا ہے.ایک اندازہ
کے مطابق انسانوں پر ایک منٹ میں ان شعاعوں کے پچیس سے تمہیں ہزار ذرات کی مسلسل یلغار ہو
رہی ہے.یہ ضروری ہے کہ فلکیاتی شعاعوں کو ان کی اپنی اصل ابتدائی شکل میں سطح زمین پر پہنچنے سے
روکا جائے.مذکورہ بالا حفاظتی تہیں اسی مقصد کیلئے بنائی گئی ہیں.صرف آکسیجن اور نائٹروجن کے
ایٹموں کے ساتھ بار بار تصادم کے نتیجہ میں پیدا ہونے والی ثانوی شعاعیں ہی ہیں جو بالآخر سطح زمین
تک پہنچتی ہیں.جیسا کہ آسمان کے تعلق میں، اُوپر بیان کیا گیا ہے قرآن کریم نے ”میزان“ کی اصطلاح
استعمال فرمائی ہے جس کے معنی ہیں تو ازن یا کوئی ایسی چیز جس سے توازن کا تعین کیا جاسکے.زمین
اور زمینی اشیاء کے تعلق میں قرآن کریم نے اسی مصدر سے نکلا ہوا ایک اور لفظ استعمال فرمایا ہے.وہ
میزان کا مصدر ”وزن“ ہے چنانچہ میزان مذکورہ بالا دونوں معانی اپنے اندر سموئے ہوئے ہے.اس
مادہ سے ایک اور لفظ ” موزون ہے یعنی ایسی چیز جو کامل توازن یا تناسب سے بنائی گئی ہو.کیا ساری دنیا میں قرآن کریم کے علاوہ کوئی بھی ایسی کتاب موجود ہے جس نے اس قدر
پیچیدہ اور مشکل مضامین اتنی سلاست، سادگی اور خوبی سے بیان کر دیئے ہوں؟ یہ ایک ایسی کتاب
ہے جو گہرے علمی اور سائنسی مضامین کو اس قدر روانی اور خوبی سے بیان کرتی ہے کہ انسان حیران رہ
جاتا ہے.قرآن کریم عصر حاضر کے مسائل اور معاملات کو بھی زیر بحث لاتا ہے حالانکہ یہ آج سے
چودہ سوسال قبل نازل ہوا جو انسانی عقل اور علم کے اعتبار سے آج سے یکسر مختلف دور تھا.قرآن کریم
قدرت کے پیچیدہ اسرار اور ہر تخلیق میں مخفی مظاہر فطرت سے جس انداز میں پردے اُٹھاتا ہے اسے
دیکھ کر انسان حیران اور ششدر رہ جاتا ہے.بعض ناقدین اسلام اور بعض دوہر یہ بھی یہ الزام لگاتے ہیں کہ قرآن کریم کلام الہی نہیں بلکہ محض
حضرت اقدس محمد مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے.حالانکہ اگر ایسا ہوتا تو بجائے فطرت کے
سربستہ راز کھولنے کے قرآن کریم بذات خود ایک بہت بڑا معمہ ہوتا.حیرت کی بات تو یہ ہے کہ
حضرت اقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام لگاتے ہوئے وہ اس بات کو کس طرح بھول جاتے ہیں
Page 39
زمین کا ماحولیاتی نظام
27
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اُمی محض تھے اور ایسے ملک میں پیدا ہوئے تھے جس کا ان پڑھ لوگوں
کی سرزمین کہ کر ٹھٹھہ اُڑایا جاتا تھا.ملک عرب کے ایک طرف ایران کی انتہائی ترقی یافتہ تہذیب
تھی تو دوسری جانب وسیع و عریض اور عظیم الشان رومی سلطنت علم کے ایک ایسے گہوارے کی صورت
میں قائم تھی جہاں فلسفہ اور سائنس اعلی پیمانے پر پروان چڑھ چکے تھے.یہ دونوں ہم عصر عظیم الشان
طاقتیں ملک عرب کو تضحیک اور تخفیف کی نظر سے دیکھا کرتی تھیں گویا جہالت اسی سرزمین سے پھوٹتی
ہے.پس علم کے اس عظیم سر چشمے یعنی قرآن کریم کو ایسی سرزمین میں رہنے والے حضرت اقدس محمد
مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام قرار نہیں دیا جا سکتا بلکہ یہ صرف اور صرف خدا کا ہی کلام ہو سکتا ہے.زمین:
زمین کی تخلیق کے متعلق قرآن کریم کے بیان کردہ توازن کے اصولوں میں سے چند ایک
مثالیں وضاحت کیلئے ذیل میں درج کی جاتی ہیں:
وَالْأَرْضَ مَدَدْنَهَا وَالْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ
موزون
(20:15 31)
ترجمہ: اور زمین کو ہم نے بچھا دیا اور اس میں ہم نے مضبوطی سے گڑے ہوئے
( پہاڑ ) ڈال دیئے اور اس میں ہر قسم کی متناسب چیزا گائی.یہ آیت اس طرف اشارہ کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو کامل توازن کے ایک
جیسے ہی اصولوں پر پیدا فرمایا ہے.چنانچہ زمین اور آسمان کے مابین جو کچھ بھی تخلیق کیا گیا ہے وہ
قوانین عدل کا پابند ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے نہایت مناسب طور پر آسمان کو ”میزان اور زمین کو
موزون قرار دیا ہے.اس میں یہ بھی اشارہ پایا جاتا ہے کہ زمین بذات خود متوازن نہیں ہوگئی بلکہ
توازن پیدا کرنے والی ایک برتر اور بالا بیرونی طاقت نے اسے متوازن کر رکھا ہے.لفظ میزان کا تعلق عدل کے آسمانی اصولوں کے ساتھ ہے اور اس میں واضح طور پر دیگر اشیاء
میں توازن پیدا کرنے کا ذریعہ ہونے کا مفہوم بھی داخل ہے.پس زمین پر نظر آنے والا اصول عدل
اپنی کسی اندرونی خوبی سے پیدا نہیں ہوا بلکہ آسمان کا عطا کردہ ہے.یہاں ہمیں اس حقیقت کا بھی
عرفان ہوتا ہے کہ زمین پر موجود ہر ایک مادی چیز کی فضیلت کا انحصار آسمانی اصولوں کے ساتھ ہم
آہنگی پر ہے.اسی طرح اس سے یہ معقول نتیجہ بھی نکلتا ہے کہ ہر نیکی اور بھلائی کی طرف دنیا کی
رہنمائی کرنے کے سب سے زیادہ اہل خالص آسمانی وجود ہی ہیں.چنانچہ فرمایا:
Page 40
28
عدل، احسان اور ایتاء ذي القربى - حصه اول
وَأَثْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونِ (المجر 20:15)
ترجمہ: اور اس میں ہر قسم کی متناسب چیزا گائی.زمین پر ہر ایک چیز کامل عدل کے عظیم قانون فطرت کے زیر اثر نمو پذیر ہے.اس قانون سے
کسی کو کوئی مفر نہیں ہے.الہی قوانین فطرت کے تابع ہی زمین پر ہر شے پروان چڑھ رہی ہے.اس سیاق و سباق میں عربی کا لفظ انبتنا ، یعنی ہم ہی روئیدگی نکالنے والے ہیں، خاص توجہ کا
طالب ہے.عموماً سمجھا جاتا ہے کہ یہ لفظ صرف نباتاتی افزائش کیلئے استعمال کیا جاتا ہے.لیکن یہ
درست نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انسانی پیدائش اور نشو و نما کیلئے بھی یہی لفظ استعمال
فرمایا ہے.چنانچہ سورہ نوح کی درج ذیل آیت میں لفظ نبات زمین پر انسان کی تخلیق اور تدریجاً
نشو و نما کیلئے استعمال ہوا ہے:
وَالله أَنْبَتَكُم مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ( نوح 18:71)
ترجمہ: اور اللہ نے تمہیں زمین سے نبات کی طرح اگایا.اس آیت میں انسان کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس کی پیدائش اور نشوونما کے متعلق
قطعیت کے ساتھ فرماتا ہے کہ یہ اسی طریق پر ہوئی ہے جس طرح نبات“ کا لفظ بیان کر رہا ہے
جس کے معنی ہیں ”نباتاتی نشو و نما“.پہاڑ :
اب ہم سورۃ الحجر کی بیسویں آیت کو سورۃ لقمان کی گیارہویں اور بارہویں آیت سے ملا کر
پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح مؤخر الذکر آیت میں اسی زیر بحث مضمون کی تفصیل بیان کی گئی
ہے.فرمایا:
وَالْأَرْضَ مَدَدْنَهَا وَالْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ
مَّوْزُون
(20:15 31)
ترجمہ: اور زمین کو ہم نے بچھا دیا اور اس میں ہم نے مضبوطی سے گڑے ہوئے
( پہاڑ ) ڈال دیئے اور اس میں ہر قسم کی متناسب چیزا گائی.خَلَقَ السَّمَوتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ
تَمِيْدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا
Page 41
زمین کا ماحولیاتی نظام
فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ هُذَا خَلْقُ اللهِ فَأَرُونِي مَا ذَا خَلَقَ
الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ بَلِ الظَّلِمُونَ فِي ضَللٍ مُّبِينِ )
(لقمان 11:31 و12)
ترجمہ: اس نے آسمانوں کو بغیر ایسے ستونوں کے بنایا جنہیں تم دیکھ سکو اور زمین
میں پہاڑ بنائے تا کہ تمہیں خوراک مہیا کریں اور اس میں ہر قسم کے چلنے والے
جاندار پیدا کئے اور آسمان سے ہم نے پانی اتارا اور اس (زمین) میں ہرفتم
کے عمدہ جوڑے اگائے.یہ ہے اللہ کی تخلیق پس مجھے دکھاؤ کہ وہ ہے کیا جو اس
کے سوا دوسروں نے پیدا کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ظلم کرنے والے کھلی کھلی
29
29
گمراہی میں ہیں.یہاں پہاڑوں کیلئے رواسی“ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جس کے معنی ہیں، مضبوطی سے
گہری گاڑی ہوئی چیز.عرب پہاڑوں کیلئے یہی لفظ استعمال کیا کرتے ہیں.قرآن کریم کے اکثر
تراجم میں پہاڑوں کے تعلق میں تَمِیدَ بِكُمْ “ کا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ ان کی تخلیق کا مقصد
بنی نوع انسان کو زلزلوں کی تباہ کاریوں سے محفوظ رکھنا ہے جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے.زلزلوں
کے اکثر مراکز سطح زمین سے بلند پہاڑوں میں ہی واقع ہیں یا پھر سمندر کی تہوں میں آتش فشاں
پہاڑوں میں چھپے ہوئے ہیں.پس اللہ تعالیٰ کے کلام کا ایسا ترجمہ کرنا جو اس کے فعل یعنی تخلیق سے
متصادم ہو منا سب نہیں.در اصل تَمِيدَ بِكُمْ کا لفظ مادَ يَمِيدُ سے مشتق ہے جس کے ایک معنی کھانے کیلئے
دستر خوان کی تیاری ہے.اس معنی کی رو سے ترجمہ یہ ہونا چاہئے:
”ہم نے مضبوطی سے گڑے ہوئے پہاڑوں کو پیدا کیا تا کہ وہ تمہارے لئے
خوراک مہیا کرنے کا ذریعہ ثابت ہوں.“
خلاصہ کلام یہ کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو اس لئے پیدا نہیں فرمایا کہ یہ بنی نوع انسان کو زلزلوں
سے محفوظ رکھیں بلکہ زندگی کے قیام کا انحصار انہی پہاڑوں پر ہے.غذا مہیا کرنے کا نظام جو زندگی
کیلئے ضروری ہے انہی کے سہارے قائم و دائم ہے اور لفظ موزون کی بہترین تصویر پیشی ہے.سطح ارض کا صرف تین فیصد حصہ خشکی پر مشتمل ہے جو پانچ براعظموں میں منقسم ہے.باقی ستر
فیصد سمندروں اور جھیلوں پر مشتمل ہے لیکن جو پانی ہم دیکھتے ہیں صرف یہی نہیں ہے بلکہ حیرت انگیز
Page 42
30
عدل، احسان اور ایتاء ذي القربى - حصه اول
بات یہ ہے کہ کل پانی کا پچھتر فیصد حصہ شمالی نصف کرہ کے پہاڑوں پر برف کی صورت میں جا پڑا
ہے.اگر پہاڑ اس جھے ہوئے پانی کو ذخیرہ نہ کریں اور یہ ساری برف پکھل کر سمندروں میں شامل ہو
جائے تو باقی ماندہ میں فیصد خشکی بھی مکمل طور پر پانی میں ڈوب جائے گی اور ساری سطح زمین کو سمندر
ڈھانپ لیں گے.زمین پر پانی کے توازن کو برقرار رکھنے میں پہاڑ بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں.اسی طرح
انسانوں اور پودوں کے استعمال کیلئے پانی کی تطہیر میں بھی پہاڑوں کا کردار بہت اہم ہے.یہ ایک
لمبی داستان ہے کہ کس طرح پانی سمندروں سے پہاڑوں پر جاتا اور پھر واپس سمندروں میں آتا ہے
تاہم اس سارے چکر کے نتیجہ میں زمین پر موجود نباتاتی اور حیوانی زندگی کیلئے یہ پانی استعمال ہوتا ہے
اور آلودہ پانی بہ کر سمندروں میں شامل ہو جاتا ہے.آبی بخارات کے پانی یا برف بن کر نیچے گرنے کے عمل میں بھی پہاڑ ایک اہم کردار ادا کرتے
ہیں.قطبین اور بلند پہاڑی علاقوں میں اکثر آبی بخارات بارش کی بجائے برف بن کر گرتے ہیں اور
پھر برف کی سخت سلوں اور گلیشئر کی صورت اختیار کر لیتے ہیں.برف کے ان بڑے بڑے پہاڑوں پر کشش ثقل مسلسل کام کر رہی ہے جو برف کی اس توانائی
کو جو بلندی پر ہونے کی وجہ سے اس میں ہوتی ہے، کم کرتی رہتی ہے.یہ ایک طبعی قانون ہے کہ جب
برف کو زور سے دبایا جائے تو جہاں دباؤ سب سے زیادہ ہو گا وہاں درجہ حرارت بڑھ جائے گا جس
کے نتیجہ میں برف پگھلنا شروع ہو جائے گی.ایسی جگہوں پر جہاں درجہ حرارت منفی 600 تک گر جاتا
ہے وہاں بھی گلیشئر ز کے نیچے برف ہمیشہ پھلتی رہتی ہے.چنانچہ گلیشئر جہاں پہاڑ کی سطح سے جڑا
ہوتا ہے وہاں درجہ حرارت بڑھنے سے وہ پکھلنے لگتا ہے نیچے پہاڑ پر اس کی گرفت مضبوط نہیں رہتی اور
وہ نیچے پھیلنے لگتا ہے اور اپنے ساتھ بڑے بڑے پتھروں اور چٹانوں کو گھسیٹتا، رستے میں حائل تمام
رکاوٹوں
کو تہس نہس کرتا چلا جاتا ہے جس کے نتیجہ میں بڑے بڑے پتھر اور چٹانیں بے شمار چھوٹے
چھوٹے پتھروں اور سنگریزوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں.اس عمل سے نمک بھی حاصل ہوتا ہے.اگر
یہ مذکورہ بالا قانون نہ ہوتا تو سمندروں کا سارا پانی برف بن کر قطبین اور پہاڑوں پر اکٹھا ہو جاتا جس
کا نتیجہ یہ نکلتا کہ بالآخر بنی نوع انسان صفحہ ہستی سے کلیہ نابود ہو جاتے.پہاڑ زندگی کیلئے اس طرح بھی ایک سہارا ہیں کہ یہ زمین کی زرخیزی میں مختلف طریق سے اہم
کردار ادا کرتے ہیں.یادر ہے کہ زمین کی زرخیزی کیلئے جو مصنوعی کھادیں استعمال کی جاتی ہیں وہ
Page 43
زمین کا ماحولیاتی نظام
31
زیادہ تر ایمونیم کے نمکیات پر مشتمل ہوتی ہیں.جب بارش برسانے والے برقی چارج شدہ بادلوں
کو تیز ہوائیں پہاڑوں کی طرف لے جاتی ہیں تو ان میں اچانک برقی طوفان پیدا ہوتے ہیں اور
بجلیاں
کڑکتی ہیں جس سے پانی کے قطرات اور نائٹروجن گیس، ایمونیم کے نمکیات میں تبدیل ہوکر
بارش یا برف میں شامل ہو جاتے ہیں.بعض اندازوں کے مطابق اس عمل سے گھنٹے بھر میں اتنی مقدار
میں کھاد پیدا ہو جاتی ہے جتنی انسانی ہاتھ سے لگائی گئی ایک صنعت سال بھر میں پیدا کرتی ہے.ان
تمام مظاہر کا تفصیلی مطالعہ در حقیقت اُن علوم کی تشریح کرے گا جو پہاڑوں کے انسانی زندگی کیلئے عظیم
فوائد کے متعلق قرآن کریم میں موجود ہیں.اس سلسلہ میں اللہ تعالیٰ سورۃ حم السجدہ میں
فرماتا ہے کہ:
وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَرَكَ فِيْهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا
فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءَ لِلسَّابِلِينَ ( حم السجدة 11:41)
ترجمہ: اور اس نے اس کے مرتفع خطوں میں پہاڑ بنائے اور ان میں اس نے
برکت رکھ دی اور ان میں انہی سے پیدا ہونے والے خورونوش کے سامان.چار زمانوں میں مقدر کئے اس حال میں کہ (سب حاجتیں) طلب کرنے
والوں کے لئے وہ برابر ہیں.مختصر یہ کہ جب ہم آسمانوں اور زمین میں قوانین قدرت کے ظہور کا مشاہدہ کرتے ہیں تو ہمیں
ان میں کامل بیجہتی ، ہم آہنگی اور توازن دکھائی دیتا ہے.رات اور دن کے آگے پیچھے آنے اور موسموں
کے آدلنے بدلنے یعنی سرما سے گرما، خزاں سے بہار وغیرہ اور زمینی حیات پر ان کے مخصوص اثرات
ایسے عوامل ہیں جو اس نظام پر گہرے طور پر اثر انداز ہوتے ہیں جس کے سہارے زندگی قائم ہے.فضائی گیسوں کا باہمی توازن :
ہماری پسند نا پسند سے ماورا، ہر موسم کی اپنی ایک اہمیت ہے.ان میں سے ہر ایک الگ
الگ یا بحیثیت مجموعی سب موسم زمین کے ماحولیاتی نظام کو قائم رکھنے کیلئے ضروری ہیں خواہ یہ
مختلف انواع حیات کے تعلق میں ہو یا عناصر کے باہمی توازن کے اعتبار سے ہو.ہوا میں نائٹروجن آکسیجن، کاربن ڈائی آکسائڈ اور بعض کمیاب گیسوں کی خاص تناسب میں
موجودگی کیوں ضروری ہے؟ یہ ایسے سوال ہیں جنہیں حل کرنے کیلئے سائنسدانوں کی توجہ بڑھتی
Page 44
32
عدل، احسان اور ایتاء ذي القربى - حصه اول
جارہی ہے.یہ امر تو یقینی ہے کہ ان گیسوں کا خاص تناسب میں پایا جانا حادثاتی نہیں ہے اور یہ کہ اس
میں ذراسی کمی بیشی سے تمام ماحولیاتی نظام کا توازن بگڑ جائے گا یہاں تک کہ اگر کاربن ڈائی آکسائڈ
کی مقدار فضا میں صرف ایک فیصد بڑھ جائے تو اس کے اثرات تباہ کن ہوں گے.اخبارات میں
گرین ہاؤس ایفیکٹ (Greenhouse effect) کا جو تذکرہ ہوتا ہے اُسے ایک عام قاری کچھ
زیادہ سمجھ نہیں سکتا لیکن جب کوئی سائنس دان اس اثر کی اصل اہمیت سے انہیں آگاہ کرتا ہے تب
انہیں اس کا صحیح معنوں میں احساس ہوتا ہے.مثال کے طور پر اگر کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار چار
سے پانچ فیصد تک بڑھ جائے تو زمین پر زندگی قائم نہیں رہ سکتی.صرف کاربن ڈائی آکسائڈ کا
تناسب ہی نہیں بلکہ کرہ ہوائی میں موجود ہر گیس کا ایک خاص مقصد ہے اور یہ عین اسی تناسب
میں درکار ہے جس میں یہ موجود ہے.زمین کے کرہ ہوائی کی بالائی تہوں پر بھی یہی اصول
اطلاق پاتا ہے.بالا ئی کرہ ہوائی میں اوزون گیس کی تہ کی موٹائی اٹھارہ سے تھیں میل تک بیان کی جاتی ہے.اگر کسی حادثہ کے نتیجہ میں اوزون کا توازن بگڑ جائے تو کم طول موج رکھنے والی فلکیاتی شعاعوں کی
یلغار کا خطرہ ہے جو زندگی کیلئے انتہائی مہلک ہوتی ہے.اوزون گیس بالخصوص کم طول موج والی
بالائے بنفشی شعاعوں
کو ختم کر کے رکھ دیتی ہے.عالم نباتات اور عالم حیوانات کا باہمی توازن :
مختلف انواع حیات کے مابین پائے جانے والے تو ازن اور اسی طرح عالم حیوانات اور
عالم نباتات کے مابین پائے جانے والے توازن کی طرف سائنسدانوں کی توجہ بڑھتی چلی جارہی
ہے.اس توازن کی بعض شکلیں مندرجہ ذیل ہیں:
----- جانداروں کا اپنے مخصوص ماحول کے لحاظ سے توازن
--- شکاری اور ان کا شکار بننے والے جانوروں کا باہمی توازن
----- مچھلیوں کی پہاڑوں میں اپنی جائے پیدائش سے سمندروں کی طرف نقل مکانی
اور پھر سمندروں سے اپنی جائے پیدائش کی جانب واپسی میں پایا جانے والا توازن.----- دریاؤں اور جھیلوں کے باہمی توازن کا قائم رکھنا اور ان میں پائی جانے والی
مخلوقات کا تبادلہ یعنی دریاؤں سے جھیلوں میں آنا اور پھر جھیلوں سے واپس دریاؤں میں لوٹ جانے کا
متوازن نظام.
Page 45
زمین کا ماحولیاتی نظام
33
ہے،
سائنسدان اس پر اور اس جیسے دیگر بہت سے موضوعات پر تحقیق کر رہے ہیں.ہر نئی دریافت
انہیں فطرت میں پائے جانے والے گہرے اسرار کی طرف متوجہ کرتی ہے.اس سارے ماحولیاتی
نظام میں، جو جاندار اور بے جان اشیاء اور ان کے باہمی تعاون کا احاطہ کئے ہوئے
کارفرما اصول عدل کو بیان کرنے کیلئے موزون سے بہتر لفظ کسی کے ذہن میں آہی نہیں سکتا.المختصر قرآن کریم کا بیان کردہ قانونِ عدل کائنات کے ذرے ذرے پر حاوی ہے.اس
موضوع پر بہت کچھ کہا اور لکھا جا چکا ہے لیکن یہ بھی نہ ختم ہونے والا موضوع ہے.یہاں اس مضمون کو
پیچیدہ سائنسی اصطلاحات کے حوالے سے زیر بحث لانا غالبا مناسب نہیں ہوگا کیونکہ یہ بحث دلچسپ
سہی لیکن عام آدمی کی سمجھ سے بالا ہے.
Page 46
34
عدل، احسان اور ایتاء ذي القربى - حصه اول
4- عالم حیوانات
جہاں تک فلاسفروں کا تعلق ہے تو ان میں سے بعض کے نزدیک تخلیق کائنات کسی خالق کی
محتاج نہیں ہے.ان کے خیال میں یہ از خود جاری رہنے والا ایک اندھا ارتقائی عمل ہے.ظاہر ہے کہ
وہ اسی اندھے اصول کی بنیاد پر انسانی فطرت کو بھی سمجھنا اور اس مسئلہ کو سلجھانا چاہتے ہیں.وہ تجویز کرتے ہیں کہ انسان پر کسی قسم کی اخلاقی پابندیاں عائد نہیں ہونی چاہئیں بلکہ اسے اپنی
مرضی سے زندگی بسر کرنے کا اسی طرح مکمل اختیار ہونا چاہئے جیسا کہ جانوروں کو حاصل ہے.اس
تناظر میں ہمیں ان کے ہاں اللہ تعالیٰ جیسی کسی بھی بیرونی طاقت کا کوئی کردار دکھائی نہیں دیتا جو ایک
بالا ہستی کے طور پر انسان کیلئے کوئی ضابطہ حیات وضع کرے.ان کے نزدیک انسانی زندگی میں عدل
کا تصور در حقیقت عقل انسانی کی تدریجی ترقی کا مرہون منت ہے جس نے انسانی معاشرہ کی ترقی
کیلئے نہایت لمبے تجربات کی روشنی میں کچھ قواعد وضوابط وضع کرنے شروع کئے.ان میں سے کچھ کا
تعلق عدل سے بھی ہے.مذہبی نقطہ نظر اس سیکولر معاشرتی نظریہ سے واضح طور پر متصادم ہے.مذہب ہمیں یہ تعلیم دیتا
ہے کہ انسان میں صحیح یا غلط کے بارہ میں فیصلہ کرنے کی قوت ایک خاص مقصد کیلئے ودیعت کی گئی ہے
اور وہ مقصد یہ ہے کہ انسان یہ فیصلہ کرے کہ کیا اسے جانوروں کی طرح اپنی جبلی خواہشات کی پیروی
کرنی چاہئے یا پھر بعض حالات میں اسے بعض کاموں سے رک جانا چاہئے.پس اگر ہمارا یہ عقیدہ
ہے کہ انسان کو یہ خوبی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئی ہے تو اس کا منطقی نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ رہنمائی بھی
خدا تعالیٰ کی طرف سے ہی ملنی چاہئے کہ اسے کیا کرنا چاہئے اور کیا نہیں کرنا چاہئے.اس بحث کو سمجھنے کیلئے چند مثالوں سے اس مضمون کی وضاحت ضروری ہے.مثلاً شیر کی جبات
اسے کہے گی کہ بھوک مٹانے کیلئے ایک جانور کو مارڈالولیکن اس بات کا فیصلہ کہ جانور کو اس طرح مارا
جائے کہ اسے کم سے کم تکلیف ہو شیر کی طاقت سے باہر ہے.یہ خدا تعالیٰ ہی ہے جس نے اسے
اپنے شکار کو مارنے کے ایسے گر سکھا دیئے جو کم سے کم تکلیف دہ ہیں یعنی جن کے نتیجہ میں غیر ضروری
تکلیف سے بچا جاسکتا ہے.عمل تقویم کے ایک لمبے عرصے تک تدریجا جاری رہنے کے نتیجے میں ایک معین تبدیلی رونما
ہوئی جس کے ذریعے جانوروں کو آہستہ آہستہ دوسروں کی تکلیف سے آگاہی حاصل ہوئی.انسانوں
Page 47
عالم حيوانات
35
میں اس شعور کا پہلا مرحلہ قریبی رشتہ داروں کی تکلیف کے احساس سے شروع ہوا اور پھر رفتہ رفتہ یہ
دائرہ دور کے رشتہ داروں تک اور بالآخر تمام بنی نوع انسان تک ممتد ہوتا چلا گیا.پھر ادنی درجہ کے
جانداروں کی تکلیف کا احساس پیدا ہوا.یہ صفت بھی ایک دوسرے سے وابستہ ہونے کے احساس
سے ہی پیدا ہوتی ہے جو کہ تمام حیوانات میں دکھائی دیتی ہے.کسی بھی مشکل اور مصیبت کی گھڑی
میں ایک ہی نوع کے جانور اکٹھے ہو جاتے ہیں.شاید یہی وجدانی رو یہ بھیڑیوں اور کتوں میں
اجتماعیت کا شعور پیدا کرتا ہے جو گروہوں کی شکل میں شکار کیلئے نکلتے ہیں.یہ اس ارتقائی عمل کی چند
ایک مثالیں ہیں جو دوسروں کے احساسات کے متعلق بڑھتی ہوئی آگہی سے جنم لیتا ہے.چنانچہ
خطرے کے وقت ہاتھی ، جنگلی بھینسے ، زیبرا اور ہرن وغیرہ اکٹھے ہو کر اپنے مشترکہ دشمن کے خلاف
رد عمل دکھاتے ہیں.یہاں ایک نوع یا گروہ کے ساتھ ایسی وابستگی کا مہم شعور نظر آتا ہے جس کی حدود
معین اور واضح نہیں ہیں بلکہ پھیل رہی ہیں.انسانی ارتقا کے ساتھ ساتھ یہی حیوانی میلان اس میں
زیادہ پختہ اور واضح ہوتا چلا گیا اور انسان میں دوسروں کیلئے ہمدردی کا جذ بہ صرف اپنے خاندان یا بنی
نوع انسان تک ہی محدود نہ رہا بلکہ اس کا دائرہ ادنیٰ درجے کے جانداروں تک بھی وسیع ہو گیا.اس
مرحلے پر انسان کسی ایسے ضابطہ اخلاق کی ضرورت محسوس کرتا ہے جس کے احساس کا دائرہ کار انسانی
حدود سے بھی آگے تک ممتد ہو.تعلیم و تربیت کا یہ قدرتی منصو بہ حیوانات کے کردار کو کنٹرول کرنے والے جینز میں ان جسمانی
تبدیلیوں پر منتج ہوا اور یہ سفراد نی انواع حیات سے اعلیٰ کی طرف مسلسل جاری رہا یہاں تک کہ انسانی
پیدائش کی منزل آپہنچی.جیسے جیسے قدرت ارتقا پذیر انواع حیات کی اپنے ماحول سے آگہی کے دائرہ
کو وسیع کرتی چلی گئی ویسے ویسے ان کے جینز پر ان کے کردار کے بعض نقوش واضح ہوتے چلے گئے
یہاں تک کہ ہر نوع حیات کا مخصوص کردار واضح طور پر دیگر انواع سے الگ دکھائی دینے لگا.ارتقا
کے سفر میں جب ہم انسانی پیدائش کی منزل پر پہنچتے ہیں تو یہ جان کر ششدر رہ جاتے ہیں کہ زندگی کی
ابتدائی حالتوں اور انسان کے مابین چند مراحل کا نہیں بلکہ بہت طویل مسافتوں کا فرق ہے.انسان
صرف انہی چیزوں کا شعور نہیں رکھتا جن کو وہ اپنے ارد گرد دیکھتا ہے بلکہ وہ ایسی انواع حیات سے بھی
آگاہ ہے جنہیں نہ تو وہ براہ راست دیکھ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے اور نہ ہی محسوس کر سکتا ہے.اسے ایسی
صلاحیت عطا کی گئی ہے جس کے ذریعے وہ مختلف قسم کی امکانی صورتوں کا تصور کر سکتا ہے.چنانچہ
ارتقا کی یہ بلند تر منزل ہی ہے جو اس کی نگاہ کو زمینی حدود سے بہت بڑھ کر لا متناہی وسعت عطا کرتی
Page 48
36
عدل، احسان اور ایتاء ذي القربى - حصه اول
ہے.یہ شعور انسان کو اس بلند تر کردار کے ادا کرنے کیلئے تیار کرتا ہے جو اس کے مقدر میں لکھا ہوا ہے
اور ساتھ ساتھ لامحدود ترقی کی اہلیت بھی اس میں پیدا کرتا چلا جاتا ہے.یہ نئی استعداد انسان اور اس
کے خالق کے مابین پل کا کام دیتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمکلام ہونے کا ذریعہ بنتی ہے.جہاں تک انسانی بقا کیلئے خوراک کا تعلق ہے تو وہ بالقوہ گوشت خور بھی ہوسکتا ہے اور سبزی خور
بھی.زمانہ قدیم سے گوشت انسانی خوراک کا ایک لازمی جزو رہا ہے، بایں ہمہ وہ صرف سبزیاں کھا
کر بھی زندہ رہ سکتا ہے، اس سے واضح ہوتا ہے کہ انسانی ارتقا میں وسعت کی سمت کیا ہے.اس کے
علاوہ ایک اہم سماجی اور اخلاقی سوال بھی اٹھایا جا سکتا ہے.انسان کا یہ اہم امتیازی وصف بھی مدنظر
رہنا چاہئے کہ اسے یہ اختیار بخشا گیا ہے کہ وہ چاہے تو اپنی جبلی خواہشات کی پیروی کرے اور چاہے
تو ان کی پیروی سے انکار دے.جب ہم انسان کو حاصل اختیارات اور ان کے استعمال کا دوبارہ جائزہ لیتے ہیں تو قانون سازی
اور ایک ضابطہ اخلاق کی ضرورت صاف ظاہر ہو جاتی ہے.اب ہم دوبارہ اسی مسئلہ کی طرف آتے ہیں
جو انسانی بقا کیلئے خوراک کے استعمال سے متعلق ہے اور جانوروں کا گوشت کھانے کے سوال پر پھر غور
کرتے ہیں.اگر انسان کو اس کی مرضی پر چھوڑ دیا جاتا تو وہ اپنی بقا کے بنیادی تقاضے کی تعمیل اور اپنے
ذوق کی تسکین کی خاطر کسی بھی جانور کو اپنا شکار بنا سکتا تھا اور یہ بھی ممکن نہیں کہ ایک شخص کا ذوق
دوسروں جیسا ہی ہو، لہذا ایسی صورت حال میں پسند کا دائرہ بہت زیادہ وسیع ہو جاتا ہے یہاں انسان
کے جبلی اوصاف کا جانوروں کی ادنیٰ حالتوں سے موازنہ کرنے کا بھی ایک اچھا موقع ملتا ہے.عالم حیوانات میں کھانے پینے کی عادات معین ہیں اور جانوروں کے عمومی رویہ میں ان کے
ذوق کے انفرادی تنوع کا کردار بہت معمولی ہے.تاہم انسانوں میں غذا اور پسند نا پسند کے وسیع
تنوع نے ان کی کھانے پینے کی عادات کو بہت پھیلا دیا ہے.انسان ارتقا کی ایک ایسی منزل پر پہنچ
چکا ہے کہ باوجود گوشت خوری کی خواہش کے ، وہ دوسری چیزیں کھا کر کنٹرول بھی کر سکتا ہے اور اپنی
اس خواہش کو دبا بھی سکتا ہے جو کہ دیگر جانوروں سے ایک بالکل مختلف رویہ ہے.اس کی ترقی یافتہ
چینی استعداد میں اور آگہی کا وسیع دائرہ اس کے لئے ایک بلند تر مقصد کی خاطر اپنی اندرونی خواہشات
کو قربان کرنا ممکن بنا دیتا ہے.اور باوجود گوشت خوری کی شدید خواہش کے کسی متبادل چیز میں تسکین
پالیتا ہے اور اس خواہش کے سامنے جھکنے سے وہ خود کو روک سکتا ہے.جانور تو محض اپنے وجدان کے تابع ہوتے ہیں جبکہ انسان اپنا راستہ خود پسند کرتا ہے.وہ
Page 49
عالم حيوانات
37
گوشت خور بھی بن سکتا ہے اور سبزی خور بھی.یہ ایک حیرت انگیز بات ہے کہ انسانی دانت بھی دونوں
قسم کی غذاؤں کے مطابق اپنا کام سرانجام دے سکتے ہیں.انسانوں اور جانوروں کے رویہ میں ایک اور بہت بڑا فرق یہ بھی ہے کہ بعض صورتوں میں
انسان جانوروں سے کہیں بڑھ کر درندگی پر اتر سکتا ہے.درندے اپنی نوع کے جانوروں کو ہر گز نہیں
کھاتے لیکن انسان ایسا کر سکتا ہے.چنانچہ افریقہ کے بعض انتہائی پسماندہ علاقوں میں آج بھی آدم
خورانسان پائے جاتے ہیں.وہاں ایسے قبائل ہیں جو سرحد پار قبائیلیوں کو گوشت کھانے کی نیت سے
پکڑتے اور مار ڈالتے ہیں.یہ عظیم الشان جشن ڈھول کی تھاپ پر منایا جاتا ہے.شیروں، بھیڑیوں
اور کتوں میں بھی اپنے ہم جنسوں کیلئے ایسا سلوک کہیں دکھائی نہیں دیتا یہاں تک کہ خواہ وہ بھوکوں مر
رہے ہوں پھر بھی وہ اپنے ہم جنسوں کو نہیں کھاتے.بظاہر نظر آنے والی انسانی کردار کی اس خصوصیت کا گہرائی میں جا کر جائزہ لینا چاہئے مبادا ہم
اس سے غلط نتائج اخذ کر بیٹھیں.انسان کا اپنی ہی نوع کا گوشت نہ کھا نامحض جبلی رویہ نہیں.در حقیقت
وہ چاہے تو ایسا کر بھی سکتا ہے.فطرت کا کوئی قانون اس قبیح فعل کے کرنے میں رکاوٹ نہیں بنتا.یہ تو
محض اقدار کی ایک اعلیٰ اور بلند منزل ہے جو اکثر لوگوں کو ایسے شفیع افعال سے باز رکھتی ہے.اس نکتہ کی مزید وضاحت کیلئے یہ بیان کرنا ضروری ہے کہ عین ممکن ہے کہ ہم جنسوں کو نہ کھانے
کے رجحان کے اعتبار سے ایک شیر انسان کی نسبت زیادہ مہذب دکھائی دے لیکن ضروری نہیں کہ ہم
اس سے کوئی نتیجہ اخذ کر سکیں.شیر تو محض اپنی جبلت کے مطابق کام کرتا ہے اور اپنے معین طرزعمل
سے انحراف نہیں کرتا جبکہ انسان نے بہر حال اپنا رستہ خود چنا ہوتا ہے.انعام کا استحقاق بھی ہوتا ہے
جب اس کے پاس انتخاب کا اختیار ہو.اگر اختیار ہی حاصل نہ ہو تو انعام کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا.لیکن جہاں پر اختیارات موجود ہوں وہاں پر حقوق و فرائض اور مناسب نامناسب وغیرہ کیلئے ایک
ضابطہ اخلاق کیلئے قانون سازی کی ضرورت ہوتی ہے.چنانچہ درست انتخاب کیلئے انسان کو اللہ تعالیٰ
کی طرف سے رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، اس لئے کہ دنیا کے مختلف حصوں میں رسم و رواج،
عادات واطوار، روایات اور اقدار نیز سماجی پس منظر مختلف ہوتا ہے.الہی تعلیمات کی یہ فلاسفی دنیا
کے تمام بڑے بڑے مذاہب میں پائی جاتی ہے.پس تربیت کا ایک طویل، تدریجی اور پر پیچ سفر
ہے جس کے ذریعے انسان بالآخر انسانی رویہ کی منزل تک پہنچا ہے اور یہی انسانی طرز عمل، انسان کو
ادنی حیوانات سے ممتاز کرتا ہے.اس سفر میں انسان نے محض وہی اقدار نہیں سیکھیں جن کا تعلق عدل
Page 50
38
عدل، احسان اور ایتاء ذي القربى - حصه اول
کے زمرہ سے ہے.بلکہ احسان اور ایتاً و ذی القربی کے سبق بھی سیکھے ہیں.اس سے اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ کے معنوں پر بھی روشنی پڑتی ہے جس میں انسان کی لامحدود
ترقیات اور انعامات کا ذکر ہے جو اس کے طرز عمل کو مزید بہتری اور لطافت عطا کرتے ہیں.لیکن
اس کا سارا انحصار صحیح رستہ کے انتخاب پر ہے.اگر انسان صحیح انتخاب کرتا ہے تو مسلسل ترقی کرتا چلا
جائے گا لیکن اگر وہ کسی وقت انتخاب کی آزادی کا غلط استعمال شروع کر دے تو لازماً قعر مذلت میں
گرتا چلا جائے گا جس کا سب سے نچلا درجہ آسفل سفلین ہے.وہ اتنا بے رحم اور خود غرض ہوسکتا
ہے کہ درندوں سے بھی بدتر ہو جائے.اس کے باوجود انسان کے اندر یہ غیر معمولی صلاحیت بھی ہے کہ وہ ترقی کرتے کرتے ایسے اعلیٰ
مقام پر فائز ہو جائے جو عالم حیوانات میں اور کہیں دکھائی نہیں دیتا.انسان عدل و انصاف اور تقویٰ کی
راہوں پر قدم مارتے ہوئے ایتا عذی القربیٰ کا اعلیٰ ترین مقام حاصل کر سکتا ہے جہاں وہ ذاتی مفاد یا ذاتی
آرام کو ان لوگوں کی خاطر بھی قربان کر دیتا ہے جو در حقیقت اس کے قریبی رشتہ دار بھی نہیں ہوتے.ہم اس بارے میں کئی ایک مستثنیات بیان کر چکے ہیں.ایک قدرے مختلف استثناء بعض ایسے
بدخصلت انسانوں میں دکھائی دیتا ہے جو بلا کسی مجبوری کے معصوم بچوں کو صرف ان کا گوشت کھانے
کیلئے مار ڈالتے ہیں.بچوں پر تشدد بھی اسی زمرہ میں آتا ہے.یہاں اس امکانی خطرہ کے متعلق
قرآنی انتباہ کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ انسان أَسْفَلَ سَفِلِينَ بن سکتا ہے.ایک گروہ کی شکل میں بھی انسان محض مذہبی اور سیاسی اختلافات کے باعث دیگر بنی نوع
انسان کو ظلم وستم کا نشانہ بناتا ہے.چنانچہ جب کبھی متعصب اور پست ذہنیت رکھنے والے ملاں یا
بد اخلاق اور ظالم سیاستدان بر سر اقتدار آتے ہیں تو عدل و انصاف سے کلیہ عاری ہو جاتے ہیں.سین کی عدالت INQUISITION اس کی ایک بڑی واضح مثال ہے.ازمنہ وسطی کی اسلامی تاریخ میں بھی ایسی کئی تکلیف دہ مثالیں موجود ہیں کہ جب محض مذہبی
اختلاف کی بناء پر ملاؤں نے لوگوں کو موت کے گھاٹ اُتارا اور حکومتیں خاموش رہیں.ایسی بہیمانہ
حرکات کو سرسری نظر سے دیکھنے سے ہی دل دہل جاتے ہیں.ظلم وستم کا یہ سلسلہ ابھی اختتام کو نہیں
پہنچا بلکہ آج بھی جاری و ساری ہے اور کوئی نہیں کہ سکتا کہ انسان
ترقی کرتے کرتے اس مقام پر پہنچ
چکا ہے کہ اب اس کے وحشیانہ حالت کی طرف لوٹ جانے کا کوئی احتمال باقی نہیں رہا.خود جماعت
احمدیہ کو جس طرح مذہب کے نام پر بار بار انتہائی مظالم کا نشانہ بنایا جاتا ہے اس کے بعد محققین کیلئے
ضروری نہیں کہ وہ ایسے شواہد کی تلاش میں تاریخ کی ورق گردانی کرتے پھریں.
Page 51
عالم حيوانات
39
اس کے برعکس انسانوں میں ایسے مہذب اور اعلیٰ اخلاق کی مثالیں بھی ملتی ہیں جو عدل،
احسان اور ایتاء ذی القربی جیسی قرآنی تعلیمات کو ذہنوں میں اُجاگر کر دیتی ہیں.آج بھی جبکہ
بحیثیت مجموعی انسان اخلاقی انحطاط کا شکار نظر آتا ہے ، اعلیٰ اخلاق کی ایسی منفرد مثالیں موجود ہیں
جنہیں دیکھ کر انسان کے اچھے مستقبل کی امید پھر سے قائم ہو جاتی ہے.اس ضمن میں ایک دلچسپ واقعہ بیان کرتا ہوں جو ہے تو کہانی لیکن عدل، احسان اور ایتآ ذی القربی
کے باہمی تعلق کو سمجھنے میں ہماری مدد کرتی ہے.بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک بزرگ کسی کھلے
میدان میں بیٹھے تھے کہ اچانک ایک مصیبت کی ماری فاختہ اُن کی گود میں آن گری جس کے تعاقب
میں ایک عقاب تھا.اُنہوں نے فاختہ کو پناہ دی.اس پر باز نے سخت احتجاج کیا اور کہا کہ انصاف
کے تقاضے کے خلاف ہے کہ آپ جیسا بزرگ انسان مجھے میری محنت کے پھل سے محروم کر دے
کیونکہ قدرت نے میرے رزق کا سامان ایسے ہی کیا ہوا ہے.اس بزرگ نے یہ دلیل تسلیم کی لیکن
اس کے باوجود ان کے جذبہ ترحم نے اس بات کی اجازت نہ دی کہ وہ بے چاری فاختہ کو اس باز کا
لقمہ بننے کیلئے پیش کر دیں.چنانچہ کہانی کے مطابق انہوں نے فیصلہ کیا کہ اپنے جسم سے گوشت کا
ایک ٹکڑا کاٹ کر اس باز کو دے دیں.لہذا انہوں نے ایسا ہی کیا اور باز سے کہا کہ تم عمدہ گوشت کے
حقدار تو ہو لیکن تمہارا یہ حق نہیں ہے کہ تم اس فاختہ کا گوشت کھانے پر ہی اصرار کرو.قدرت نے
فاختہ کو ہی تمہارے لئے مخصوص نہیں کیا.تمہیں گوشت کی ضرورت ہے اور وہ میں تمہیں دے رہا ہوں
جو تمہارے لئے کافی ہونا چاہئے.یہ کہانی زیر بحث مضمون کو نہایت عمدہ رنگ میں واضح کر رہی ہے.اس میں عدل کے حقیقی معانی اور اس کے ایسے مواقع پر اطلاق کے اصولوں کی وضاحت ہے جہاں
ایک کی بقا کا انحصار دوسرے کی فنا پر ہوتا ہے.اس تناظر میں تقویم اور عدل کے قوانین کی ایک تشریح یہ ہوگی کہ ہر جانور کو اس کی بقا کا سامان
اور اس کے حصول کے ذرائع مہیا کر دیئے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہر جانور کو بقا کی جدوجہد
میں خطرات بھی در پیش ہیں.چنانچہ اس طرح ایک ایسا متوازن ایکوسٹم یعنی ماحولیاتی نظام تخلیق
کر دیا گیا ہے جو عدل کے بنیادی اصول پر جاری وساری ہے.دوسرا پہلو جو اس مثال سے خوب واضح ہو جاتا ہے یہ ہے کہ عدل ایک بنیادی اور مطلق اصول
کے طور پر کارفرما ہے اور جب کبھی بھی احسان کا عدل کے تقاضوں سے ٹکراؤ ہوگا تو عدل کو احسان پر
ترجیح دی جائے گی.احسان صرف اسی صورت میں ہوسکتا ہے جبکہ عدل قائم رہے.عدل کو قربان کر
کے احسان نہیں ہوتا.
Page 52
40
عدل، احسان اور ایتاء ذي القربى - حصه اول
اس مثال سے ایک بنیادی سوال یہ اُبھرتا ہے کہ جب عدل اور احسان میں ٹکراؤ دکھائی دے تو
تیسرا رستہ کون سا ہے جو اس مخمصہ کو حل کر سکے؟ اس بزرگ نے بیک وقت عدل اور احسان کے
تقاضے پورے کرنے کیلئے اپنے گوشت کی قربانی دینے کا رستہ اختیار کیا.اُن کا یہ طرز عمل بھی
ایتاء ذی القربی کہلائے گا کیونکہ اتنی اعلیٰ درجہ کی قربانی صرف اپنے اعزاوا قارب کیلئے ہی دی جا
سکتی ہے.ایتاء ذی القربی کے یہی وہ حقیقی معانی ہیں جو احسان اور عدل کے تعلق میں قرآن کریم
کے مطالعہ سے معلوم ہوتے ہیں اور انہی اصولوں کے تابع نظام کا ئنات چل رہا ہے.تاہم یاد رکھنا
چاہئے کہ یہ تینوں اصول ابتدائے آفرینش سے ہی اکٹھے کار فرما نہیں ہو گئے تھے.درحقیقت مادی دنیا
یعنی بے جان اشیاء کلیۂ اصول عدل کے تابع نظر آتی ہیں.زندگی نے جنم لیا تو ساتھ ہی شعور پیدا ہوا اور جیسے جیسے اس میں پختگی آتی گئی اور آگہی کا سفر
آگے بڑھتا گیا تو احسان اور ایتا عذی القربی میں بھی ترقی کا آغاز ہوا.یوں یہ دو اصول ارتقائے
حیات کے سفر میں رہنما اصول قرار پائے اور پھر یہ سلسلہ ترقی کرتا گیا.تخلیق انسانی کے مرحلہ تک یہ
آہستگی لیکن مستقل مزاجی سے آگے بڑھا ہے لیکن جب یہ اس مقام تک پہنچا جہاں حیوانی اور انسانی
زندگی کے مابین بہت بڑی حد فاصل قائم ہوگئی تو یوں لگا جیسے یہ بہت عظیم جست لگا کر آگے بڑھ گیا
ہے جس سے طرزِ حیات ہی کلیہ تبدیل ہوگئی گویا ایک نئی مخلوق نے جنم لیا ہو.انسان کی طرف سے مذکورہ بالا اصولوں کو قبول کرنے یا رد کر دینے سے عہد ساز تبدیلیوں نے
جنم لیا اور انسانی تاریخ میں ایسے رجحانات پیدا ہوئے جن کے اثرات بڑے دوررس تھے.عدل،احسان اور ایتاً عذی القربیٰ کے تعلق میں احساس کا کردار:
سوال پیدا ہوتا ہے کہ حیوانات کی نسبت انسانی احساس کیوں اس قدر مہذب اور ترقی یافتہ
ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ زندگی کے ارتقا کے ساتھ ساتھ احساس نے بھی بتدریج ترقی کی اور انسان
کی منزل پر پہنچ کر یہ اچانک بہت تیزی سے آگے بڑھنے لگا.کیونکہ انسانی سطح پر پہنچنے کے بعد جسمانی
ارتقا سے کہیں بڑھ کر روحانی ارتقا شروع ہو گیا تھا.ترقی کی مختلف منازل سے گزرنے کے طویل عرصہ بعد اس نے اپنا دائرہ اور بھی وسیع کر لیا.افراد کو اپنے ماحول کا شعور حاصل ہوا اور اپنے ہم جنسوں کے بارہ میں آگاہی اور احساس بیدار
ہو گیا.اس سے اگلے مرحلہ پر ان کے احساس اور آگہی کا دائرہ دیگر انواع حیات تک ممتد ہو گیا.بنی نوع انسان کے احساسات اپنی شدت اور وسعت کے اعتبار سے حیرت انگیز طور پر بڑھ
Page 53
عالم حيوانات
41
گئے ہیں.یہاں احساس اور شعور ا کٹھے کار فرما ہیں.ان کا باہمی فرق محض ان کے متعلقہ دائرہ کار
سے ہی تعلق نہیں رکھتا بلکہ احساس اور شعور کے معیار بھی الگ الگ ہیں.انسانوں کے ہاں کوئی
احساس بھی مہم نہیں ہوتا جیسے کسی کیڑے کو کوئی درد ہوتا ہے یا پھر غذامل جانے کی خوشی ہوتی ہے بلکہ یہ
کہیں زیادہ واضح اور شدید نوعیت کا ہوتا ہے.اس کا انسانی جسم کے مختلف افعال اور یادداشت سے
بڑا گہرا اور پیچیدہ تعلق ہے.اس سے یہ امر بہت حد تک واضح ہو جاتا ہے کہ ان دونوں استعدادوں نے ہر دائرے میں
انسانی طرز عمل کی نوک پلک سنوارنے میں بہت اہم اور پیچیدہ کردار ادا کیا ہے اور ہر پہلو سے اس پر
انمٹ نقوش ثبت کئے ہیں.جب انسانوں میں احساس اور شعور ، عدل و احسان اور ایتا عذی القربی
کے ساتھ مل کر کار فرما ہوتا ہے تو نئے خیالات، نظریات، تصورات اور عقائد جنم لیتے ہیں اور انسانی
زندگی کی تعمیر کرنے والے سب عوامل کو وسعت عطا کرتے ہیں.مختصر یہ کہ انسان کو اس کی آخری
منزل پر پہنچانے میں عدل، احسان اور ایتآء ذی القربیٰ نے ہمیشہ تعمیری یا تخریبی اعتبار سے مرکزی
کردار ادا کیا ہے.
Page 54
42
انسان بطور عالم صغیر :
عدل، احسان اور ایتاء ذي القربى - حصه اول
-5 انسانی ارتقا کا اگلا قدم
انسان تخلیق کا عظیم ترین معجزہ ہے.اس کے وجود میں کھربوں سالوں پر محیط ارتقائے حیات
سمویا ہوا ہے.یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے.ہر انسان کے اندر ارتقائے حیات کی تاریخ کا مکمل ریکارڈ
موجود ہے.انسان، عالم صغیر کی حیثیت رکھتا ہے.در حقیقت یہ زمان و مکان کے کامل امتزاج کی
ایک زندہ علامت ہے.لیکن اس موضوع پر مزید روشنی ڈالنے سے پہلے اس حیرت انگیز حقیقت کا ذکر
ضروری ہے کہ قرآن کریم انسانی تخلیق کے تمام مراحل اور بنیادی خدوخال کا پوری طرح احاطہ
کرتا ہے اور کوئی بھی قابل ذکر مرحلہ ایسا نہیں جو اس نے بیان نہ کیا ہو.تمام مخلوقات میں سے قرآن کریم نے صرف انسانی تخلیق کو کامل عدل کے کردار کی وضاحت
کیلئے سب سے بڑی علامت کے طور پر بیان
فرمایا ہے.چنانچہ فرمایا:
يَايُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبَّكَ الْكَرِيمِ الَّذِي خَلَقَكَ
فَسَونَكَ فَعَدَ لَكَ فِي أَي صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ
(الانفطار 7:82 تا 9)
ترجمہ: اے انسان تجھے اپنے رب کریم کے بارہ میں کس بات نے دھو کے میں
ڈالا ؟ وہ جس نے تجھے پیدا کیا.پھر تجھے ٹھیک ٹھاک کیا.پھر تجھے اعتدال
بخشا.جس صورت میں بھی چاہا تجھے ترکیب دی.آئیے اب اس آیت پر قدرے تفصیل سے دوبارہ نظر ڈالتے ہیں.اللہ تعالیٰ گویا انسان سے
یوں مخاطب ہے کہ اے انسان! کس چیز کے برتے پر تو اپنے خالق و مالک خدا کے سامنے اکثر رہا
ہے؟ اگر تو کائنات کی عظمت اور اس کے اسرار کو نہیں سمجھ سکتا تو کم از کم اپنی ذات میں ڈوب کر اس
کامل توازن کو دیکھ جس کے ساتھ خدا نے تجھے پیدا کیا ہے یعنی اس کا ئنات پر غور کر جو تیرے اندر
ہے.کیا پھر بھی تو خدا کے وجود کا انکار کرنے کی جرات کر سکتا ہے؟ ہم پھر کہتے ہیں کہ وہی خدا ہے
جس نے تجھے پیدا کیا، شکل وصورت دی اور حسین تناسب عطا فر مایا.اگر چہ یہ آیات چودہ سو سال پہلے نازل ہوئیں لیکن یوں لگتا ہے کہ یہ آج کے اس جدید سائنسی
دور میں نازل ہوئی ہیں.قرآن کریم کے نزول کے وقت اس بات کا کوئی تصور بھی نہیں تھا کہ انسان
Page 55
انسانی ارتقا کا اگلا قدم
43
اتنے جینیاتی مراحل سے گزرا ہے اور اس نے اتنی مختلف شکلیں اختیار کی ہیں اور اس قدر مختلف
نامیاتی مرکبات کے تناسب سے اس کی تشکیل ہوئی ہے.یہ سب کچھ ارتقا کی تاریخ کا آئینہ دار
ہے.سورۃ الانفطار کی مذکورہ بالا آیات ہرگز اُس زمانے کے انسان کے ذہن کی اختراع نہیں ہو
سکتیں.یہ آیات انسان کو یاد دلاتی ہیں کہ وہ اپنی پیدائش سے پہلے مختلف شکلوں اور صورتوں سے گزرا
ہے.ان ان گنت تبدیلیوں کیلئے نامیاتی مرکبات کے مختلف تناسب کی ضرورت تھی.انسان یہ سوچ
کر حیران رہ جاتا ہے کہ ابتدائی زمانے کے لوگوں نے ان آیات سے کیا پیغام اخذ کیا ہوگا، جو
در اصل آنے والے زمانوں سے تعلق رکھتی تھیں؟
سورۃ القیامۃ میں یہ مرکزی خیال اور بھی واضح دکھائی دیتا ہے کہ:
بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَلَوْ الْقَى مَعَاذِيْرَهُ
(القیامة 16،15:75)
ترجمہ: حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے نفس پر بہت بصیرت رکھنے والا ہے.اگر چہ وہ اپنے بڑے بڑے عذر پیش کرے.اس سے مراد یہ ہے کہ انسان اعتذار کے پردہ میں چھپ سکتا ہے.تاہم اس میں یہ صلاحیت
موجود ہے کہ وہ اپنی نیت کے پس پردہ محرکات کو جان سکے.خود کو جان سکنے کی اسی صلاحیت کا
قرآن کریم نے سورۃ الشمس کی درج ذیل آیت میں دوبارہ ذکر فرمایا ہے:
فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقُوبَهَا (الشمس 9:91)
ترجمہ: پس اس کی بے اعتدالیوں اور اس کی پر ہیز گاریوں ( کی تمیز کرنے کی
صلاحیت ) کو اس کی فطرت میں ودیعت کیا.اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ذی روح کی گھٹی میں ڈال دیا ہے کہ اس کیلئے کیا اچھا ہے
اور کیا برا.نیز یہ کہ اسے کیا کرنا چاہئے اور کس کام سے رُک جانا چاہئے.پس اپنی فطرت کی آواز کوسن
کر انسان اچھے اور برے میں تمیز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے.بالفاظ دیگر اللہ تعالیٰ نے فطرت انسانی
میں وجدان کی ایسی صلاحیت رکھ دی ہے جو پیش آمدہ خطرات کے متعلق انتباہ کرتی رہتی ہے جو اس کے
فیصلوں کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں.اسی طرح سے متنبہ کرنے کی ایسی صلاحیت عطا کی گئی ہے جو
ہمیشہ صحیح اور غلط میں تمیز کر کے اس بات
کو عملاً ناممکن بنا دیتی ہے کہ وہ نا دانستہ طور پر کوئی غلط کام کرے.جب ان آیات کو ملا کر پڑھا جائے تو علم کی نئی راہیں کھلتی ہیں.سائنسدانوں نے ان علوم کا
Page 56
44
عدل، احسان اور ایتاء ذي القربى - حصه اول
احاطہ کرنے کی کوشش کی ہے لیکن تحقیق و جستجو میں وہ جتنا آگے بڑھتے ہیں یہ مضامین اسی قدر وسعت
اختیار کرتے چلے جاتے ہیں.در حقیقت ان وسعتوں کی کوئی حد بست ہی نہیں ہے.زندگی کی
خصوصیات کو اپنے اندر سموئے ہوئے خلیات کے جامع مطالعہ کیلئے سائنسدانوں کی کئی نسلیں درکار
ہوں گی لیکن پھر بھی یہ مضمون ختم نہیں ہوگا.زندگی کے بنیادی اجزائے ترکیبی:
جب ہم انسانی جسم اور اس کے اجزائے ترکیبی پر غور کرتے ہیں تو اپنے اجسام میں ایک نہایت
پیچیدہ نظام سرگرم عمل پا کر حیران رہ جاتے ہیں.انسانی جسم اربوں خلیات سے تعمیر ہوا ہے.ہر خلیہ
دوسرے سے مختلف اور مخصوص شکل وصورت کا حامل ہے جو اس کے کام کی نوعیت کے مطابق بدلتی
رہتی ہے.یہ خلیات اپنے حجم اور شکل وصورت کے اعتبار سے کئی قسم کے ہوتے ہیں اور ان کے مختلف
حصے ہوتے ہیں.ہر حصہ جسم میں ایک مخصوص کام سرانجام دیتا ہے.لیکن نیوکلیس ان میں ایک
مرکزی کردار ادا کرتا ہے، جس کا کام بہت دقیق اور پیچیدہ ہوتا ہے.نیوکلیس خلیہ کے اندر ایک جھلی میں لپٹا ہوتا ہے.اس جھلی کے اندر کی طرف نیوکلیو پلازم
(Neucleoplasm) ہوتا ہے جس میں آر.این.اے اور ڈی.این.اے بکثرت موجود ہوتا
ہے.یہ وہ مادہ ہے جو کہ خلیہ کی تقسیم کے عمل میں نہایت بنیادی کردار ادا کرتا ہے.ایک صحت مند خلیہ
کا انحصار اس کے نیوکلیس پر ہوتا ہے.نشو ونما، میٹا بولزم یعنی خلیہ کے اندر جاری عمل تعمیر وتخریب،
افزائش نسل اور خصوصیات
کی منتقلی کیلئے یہ ایک ضروری ذریعہ ہے.مزید وضاحت کیلئے ہم یوں کہ سکتے ہیں کہ انسانی جسم میں پائے جانے والے اربوں خلیات
میں سے صرف ایک خلئے کے اندر اس سے کہیں زیادہ معلومات ذخیرہ کی گئی ہیں جو انسان کے بنائے
ہوئے کسی جدید ترین کمپیوٹر کی یادداشت میں محفوظ ہو سکتی ہیں.اس کے معنی یہ ہیں کہ اربوں خلیات
میں بالکل ایک جیسی معلومات ذخیرہ کی گئی ہیں اور ان میں سے ہر خلیہ جسمانی نظام کو چلانے میں اپنا
کردار ادا کر رہا ہے.جسم کے اندر عین صیح وقت اور درست سمت میں خلیہ کے اندر ایک عمل واقع ہوتا
ہے جو ان افعال کیلئے محرک کی حیثیت رکھتا ہے جن کی خاطر اس خلئے کو تخلیق کیا گیا ہے.اسی طرح
آر.این.اے کے ذریعے جو کہ پیغامبر خلیات ہیں معلومات کو جسم کے دیگر متعلقہ حصوں تک پہنچایا
جاتا ہے.یہ سارا کام بغیر کسی تصادم کے کامل ہم آہنگی کے ساتھ سرانجام پاتا ہے.ہمیں خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہئے کہ اس نے سائنسدانوں کے خورد بین کی مدد سے انسانی خلئے
Page 57
انسانی ارتقا کا اگلا قدم
45
کے عجائبات سے آگاہ ہونے سے بہت پہلے حضرت اقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کے
ذریعے یہ علم عطا فر ما دیا تھا.پس قرآن کریم کے اس بیان کی موزونیت اور جامعیت کو دیکھ کر انسان
حیران رہ جاتا ہے.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اُس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری تکمیل کی اور پھر عدل کی تمام
شرائط ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے تمہیں سنوارا اور کئی کامل متوازن صورتوں میں ڈھالا (الانفطار 7:82 تا9)
اُس زمانے کا انسان یہ دیکھ کر حیران ہوا ہوگا کہ قرآن کریم نے بنی نوع انسان کی تخلیق اور بناوٹ میں
توازن کے مضمون کو بیان کرنے کیلئے عدلگ“ کا لفظ ہی کیوں استعمال فرمایا ؟ اس سے پہلے کسی
بھی فلسفے یا مذہبی کتاب میں تخلیق انسانی کا مضمون اتنی وضاحت کے ساتھ بیان نہیں ہوا.66
توازن اور آگہی :
یہ امر قابل ذکر ہے کہ قرآن کریم نے مختلف مقامات پر جو اصطلاحات استعمال فرمائی ہیں ان
میں بہت لطیف ربط پایا جاتا ہے.مثلاً تمام ارضی اجسام میں توازن کار فرما دکھائی دیتا ہے جبکہ
انسانوں میں جاری اصول کو بیان کرنے کیلئے عدل کا لفظ استعمال ہوا ہے لیکن اس سے ہرگز یہ مراد
نہیں کہ انسان ” موزون نہیں ہے.عدل موزون اور میزان دونوں کا احاطہ کئے ہوئے ہے نیز اس
میں توازن اور انصاف کے متعلق شعوری احساس کا مفہوم بھی شامل ہے.پس عدل تو ازن کی ایک
بہت بلند منزل کی نشان دہی کرتا ہے جس میں شعور کا عنصر بھی شامل ہو گیا ہے.قرآن کریم کے
مطابق انسان کو عدل کے اصول پر تخلیق کیا گیا ہے جس کی رو سے وہ عظیم الشان الہی نظام عدل میں
بلندترین مرتبہ پر فائز ہے اور دیگر تمام مخلوقات سے افضل اور اشرف ہے.ابتدائے آفرینش سے ہی عدل نے قوانین قدرت کی شکل میں ایک لاشعوری کردار ادا کیا
ہے.بعد ازاں جب کائنات کا ارتقا آغاز حیات کے مرحلے تک آن پہنچا تو عدل کا یہ لاشعوری عمل،
متوازن طرز عمل کی ایک وجدانی شکل میں تبدیل ہو گیا.نیز تخلیقی اصول جو تمام ارتقائی مراحل میں
کارفرما ہوتے ہیں مکمل لاشعوری عمل یا توازن کے وجدانی عمل کے تابع ہیں.جیسا کہ قبل از میں بیان
کیا جا چکا ہے کہ شعور کی تیسری منزل تک صرف انسان ہی پہنچتا ہے.اربوں سال پر محیط ارتقا کے دوران، زندگی کی آگہی کی سطح بتدریج بلند ہوتی چلی گئی.اس تمام
سفر کا مقصد شعوری عدل کی آخری منزل کا حصول ہی تھا جو کہ انسانی ذہن اور روح کی مزید ترقی کیلئے
اور آئندہ ایک نامعلوم، اعلیٰ اور لطیف زندگی کیلئے بہت ضروری ہے.ترقی کی اس سیڑھی کا ہر زینہ
عدل ہی کا مرہون منت ہے.چنانچہ عدل کے ایک درجے سے دوسرے درجے کی طرف بڑھے بغیر
Page 58
46
عدل، احسان اور ایتاء ذي القربى - حصه اول
زندگی کے بلند تر مقامات کا حصول ممکن نہیں.عدل سے احسان نے جنم لینا تھا جس نے پھر بالآخر
اس اعلیٰ درجے کے تعلق میں بدل جانا تھا جسے قرآن کریم نے ایتا ء ذی القربیٰ کا نام دیا ہے.یعنی
غیروں کے ساتھ اپنے قریبی رشتے داروں جیسا سلوک.مختصر یہ کہ عدل کا اعمال اور کردار کے شعوری احساس کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے.یہ لفظ
انسانی کردار کو بیان کرنے کیلئے استعمال کیا گیا ہے جبکہ انسانی اعمال شعور ہی سے جنم لیتے ہیں اور ان
میں صراط مستقیم سے انحراف کا رجحان نہیں پایا جاتا.یہیں سے زندگی کے ایک نئے دور کا آغاز ہوتا ہے.
Page 59
انسانی جسم کا اندرونی توازن
-6- انسانی جسم کا اندرونی توازن
اچھے اور برے کی اندرونی کسوٹی:
47
قبل ازیں ہم سورۃ الشمس کی آیت نمبر 9 کے ایک معنی کی تفصیل بیان کر چکے ہیں اب ہم اسی
کے ایک اور پہلو کی طرف متوجہ ہوتے ہیں.اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم کو یہ صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ وہ بیماری اور صحت نیز تعمیری اور تخریبی
عمل میں تمیز کر سکتا ہے.تمیز کرنے کا یہ نظام انسان کے کسی شعوری علم کے بغیر ایک خود کار طریق پر
جاری ہے.اس کا اطلاق نہ صرف بنی نوع انسان بلکہ تمام انواع حیات پر ہوتا ہے.ہرادنی اور اعلیٰ
نوع حیات کو ایسا اندرونی نظام ودیعت کیا گیا ہے جو اُ سے آگاہ کرتا ہے کہ اس کے وجود کی چھوٹی سی
دنیا میں اس
کیلئے کیا اچھا ہے اور کیا برا.یہاں تک کہ امیبا کی صحت اور بیماری کی بھی اپنی حدود ہیں کہ
اسے کس چیز سے پر ہیز کرنی چاہئے اور کس چیز کے حصول کی کوشش کرنی چاہئے.لیکن انسان میں یہ
صلاحیت اتنی ترقی یافتہ اور پیچیدہ ہے کہ اس کا سرسری سا مطالعہ ہی حیران و ششدر کر دیتا ہے.انسانی زندگی کی ہر سطح پر چناؤ اور رد کر دینے کا عمل بڑی جامعیت کے ساتھ جاری وساری
ہے.مندرجہ ذیل چھوٹی سی مثال اس کی بخوبی وضاحت کرتی ہے.بھوک انسان کو اس بات سے
آگاہ کرتی ہے کہ اسے توانائی کی ضرورت ہے.چنانچہ دیکھنے، سونگھنے، چھونے ، چکھنے حتی کہ بعض
اوقات سننے کی جس بھی ایک ایسے آدمی کیلئے جسے توانائی کی ضرورت ہوتی ہے فوراً اپنا کام شروع کر
دیتی ہے کہ اس کیلئے کیا اچھا ہے اور کیا برا.چنانچہ جیسے ہی انسان کسی غذا کا کوئی لقمہ چبانا شروع کرتا
ہے تو ذائقہ اور حرارت کی حسیات، دانت، لعاب دہن کے غدود، جبڑوں کی ہڈیاں اور عضلات
غرضیکہ تمام اعضاء باہم پوری ہم آہنگی کے ساتھ اپنا اپنا کردار ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں.آخر کار
جب کوئی چیز نگل لی جاتی ہے تو چناؤ کا عمل خوراک کو اُس کے سادہ تر اجزا میں توڑنے اور غیر ضروری
فاضل مادوں سے پاک کرنے کے سلسلہ میں اور بھی گہرا اور اہم ہو جاتا ہے.چنانچہ انسان کو بیکٹیریا
اور وائرس کے مضر اثرات سے بچانے کیلئے ہر قسم کا ضروری انتظام کیا گیا ہے.ان مراحل کے بعد یہ
نیم ہضم شدہ غذا ایسے کیمیائی اجزا میں تبدیل کر دی جاتی ہے جو بآسانی جزو بدن بن سکتے ہیں اور
نسبتا زیادہ پیچیدہ نامیاتی مرکبات میں ڈھل سکتے ہیں.یہ چند ایک مثالیں ہیں جو اختصار کے ساتھ نہایت سادہ رنگ میں بیان کی گئی ہیں کہ کس طرح
Page 60
48
عدل، احسان اور ایتاء ذي القربى - حصه اول
اللہ تعالیٰ نے وہ سارا نظام عطا فرمایا ہوا ہے جو خوراک کو محفوظ طور پر ہضم کرنے کیلئے ضروری ہے.اگر
خدانخواستہ توازن بگڑ جائے تو زندگی اور صحت کا معیار بری طرح متاثر ہوگا.یہ توازن اور تناسب اتنا
معین اور کامل ہے کہ اس میں معمولی سا بگاڑ بھی زندگی کیلئے موت کا پیغام ثابت ہوسکتا ہے.سورۃ الشمس کی آیت نمبر 9 میں استعمال ہونے والے لفظ ”فجور سے ایسے تغیرات مراد لینا جو
کہ صحت کیلئے خطرناک ہوں بالکل صحیح ہو گا جبکہ اسی آیت کا لفظ ” تقوی“ اس صلاحیت کی طرف
اشارہ کر رہا ہے جس کے ذریعے انسان ایسے خطرات سے بچنے کی کوشش کرتا ہے جو بالآخر بیماری
یا موت پر منتج ہوتے ہیں.پس انسانی جسم کے تعلق میں سورۃ الشمس کی یہ آیت اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ علم الاعضاء
تشریح الابدان ، اعصابی نظام، جگر کا نظام، وریدی نظام، غدودوں کا نظام اور دفاعی نظام سب کو یہ علم
ودیعت کیا گیا ہے کہ ان کیلئے کیا اچھا ہے اور کیا برا.مذکورہ بالا نظاموں میں سے کسی ایک کے تفصیلی
مطالعہ کو ضبط تحریر میں لانے کیلئے کئی جلدیں درکار ہوں گی پھر بھی یہ مضمون ختم نہیں ہوگا.لیکن اسے
سحر انگیز اور حیرت انگیز کہ دینا بھی تو سادہ لوحی ہی ہوگی.انسانی زندگی کے باریک در باریک اور تہ در تہ
اسرار کا مشاہدہ کرنا ایسا ہی ہے جیسے ایس کو ونڈر لینڈ میں چھوڑ دیا جائے لیکن انسانی تخلیق کے عجائبات
کے سامنے تو حیران کن اور پر اسرار کہانیاں بالکل بیچ ہیں.ہم یہ دیکھ کر ورطہ حیرت میں ڈوب جاتے ہیں کہ جسمانی افعال کس طرح متعلقہ قرآنی بیانات
کی مکمل تصدیق کرتے ہیں.انسان میں بیماری کا رجحان اور پھر قریباً تمام بیماریوں کے خلاف اس
میں دفاعی صلاحیت کا موجود ہونا ایک حیرت انگیز بات ہے یہاں تک کہ کینسر جیسا موذی مرض بھی
ماہر معالجین کی کسی مداخلت کے بغیر ٹھیک ہو سکتا ہے.طبی سائنس کی تاریخ میں کینسر کے بعض آخری
درجے پر پہنچے ہوئے ایسے کیس بھی ریکارڈ ہوئے ہیں جن میں مریض مکمل شفایاب ہو گئے اور ڈاکٹر
آج تک یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ یہ کیونکر ممکن ہوا؟ ماہرین کا سارا علم اس وقت دھرے کا دھرا رہ جاتا
ہے جب بستر مرگ پر پڑا ہوا ایک مریض رو بصحت ہو کر از سر نو زندگی کا آغاز کر دیتا ہے جبکہ شفا کی
بظاہر کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی.سائنسدانوں کی متفقہ رائے یہ ہے کہ انسانی جسم کے دفاعی نظام کے
اسرار کو ابھی تک محض سطحی طور پر ہی سمجھا جاسکا ہے پھر بھی ہم پورے وثوق سے کہ سکتے ہیں کہ ہمارے
دفاعی نظام میں لامتناہی امکانات موجود ہیں.دفاعی نظام کامل ہونے کے باوجود انسان کو ابدیت عطا نہیں کرسکتا.کیونکہ ہر نظام کے ساتھ
Page 61
انسانی جسم کا اندرونی توازن
49
اس کا ایک برعکس نظام بھی جاری وساری ہے جو اس کی آخری فنا کیلئے اپنا معین کام کرتارہتا ہے.پس
ہر چیز کمال درجہ پر متوازن اور متناسب ہے.انسانی جسم کے ہر خلیہ کی زندگی کی میعاد پہلے سے طے
ہے اور جینز پر نمایاں (Dominant) اور خوابیدہ (Recessive) صفات کے پیچیدہ نقوش کی
صورت میں ثبت ہے.یہ بھی واضح طور پر پہلے سے ہی طے ہے کہ کسی بھی عضو کی نشو ونما کی رفتار اس
کی موت کی رفتار سے کب تک زیادہ رہے گی؟ نیز یہ بھی کہ نشو و نما کی رفتار اور موت کی رفتار کب تک
یکساں رہے گی اور کب مؤخر الذکر رفتار بڑھ جائے گی اور فتنا کا عمل بقا کے سلسلہ پر غالب آجائے گا ؟
پس اس سارے عمل میں کچھ بھی اتفاقی یا حادثاتی نہیں ہے.جسمانی نشو ونما:
وضاحت کیلئے ایک سادہ سی مثال یعنی دانت کی نشو و نما کا مطالعہ کرتے ہیں.ہمارا اندورونی
نظام دودھ کے دانتوں کی نشوونما کی رفتار اور ان کے خراب ہو جانے کی رفتار کی مسلسل نگرانی کرتا ہے نیز
اسے ایک مناسب حد میں رکھتا ہے.چنانچہ چند سالوں تک نشو و نما کی رفتار، شکست وریخت کی رفتار
سے زیادہ رہتی ہے.اس سے اگلے مرحلے پر ان دونوں کی رفتار کچھ عرصہ تک یکساں رہتی ہے جس کے
بعد شکست وریخت کی رفتار بڑھ جاتی ہے اور دودھ کے دانتوں کے دن پورے ہو جاتے ہیں جس کے
بعد بلوغت کے دانتوں کی افزائش کا دور شروع ہوتا ہے.اس دور کے آغاز میں افزائش کی رفتار شکست
وریخت کی رفتار سے کہیں زیادہ ہوتی ہے.مقررہ لمبائی، چوڑائی اور موٹائی حاصل کر لینے تک ان کی
نشو ونما کی رفتار زیادہ ہی رہتی ہے لیکن اس کے بعد نشو ونما اور شکست و ریخت کی رفتار باہم بالکل
یکساں اور متوازی ہو جاتی ہے اور سوائے اس کے کہ دانت کسی بیماری کی وجہ سے یا حادثہ کی بناء پر
خراب ہو جائیں وہ بالکل صحت مند رہتے ہیں اور بظاہر ان کے حجم وغیرہ میں کوئی تبدیلی نہیں آتی.لوگ عموماً یہی سمجھتے ہیں کہ دانتوں
کی نشو ونما مکمل ہوئی اور اب یہ بڑھنا بند ہوگئے ہیں حالانکہ یہ
معصومانہ سا خیال حقیقت سے بہت دور ہے.کیونکہ اگر دانتوں کی افزائش کا عمل رک جائے تو چند
ہفتوں یا مہینوں کے اندر اندر سارے دانت گھس جائیں اور ان
کا کچھ بھی باقی نہ بچے اس کے برعکس اگر
دانتوں کی نشو و نما کی ابتدائی رفتار برقرار رہے تو یہ بڑھتے بڑھتے اس قدر لمبے ہوجائیں کہ نچلے دانت
کھوپڑی کو پھاڑ کر اوپر نکل جائیں اور بالائی دانت جبڑے سے نیچے لٹکتے ہوئے دکھائی دینے لگیں.الغرض یہ کوئی بے ہنگم سلسلہ نہیں بلکہ ایک با قاعدہ نظام کے تابع ہے.ایک مقررہ مدت تک
شرح افزائش کو برقرار رکھنے اور پھر بر وقت اس میں تبدیلی پیدا کرنے کے تمام عوامل طبعی طور پر
Page 62
50
عدل، احسان اور ایتاء ذي القربى - حصه اول
متوازن ہیں اور یہ سب کچھ انسانی تخلیق کے بنیادی ڈھانچے پر معین اور واضح رنگ میں لکھا ہوا موجود
ہے.یہ دیکھ کر دماغ چکرا جاتا ہے کہ انسانی جسم کی ساخت کا تمام تر منصو بہ کس طرح اپنے وقت پر
بار یک در بار یک تفاصیل کے ساتھ عملی رنگ میں ظاہر ہوتا چلا جاتا ہے.انسانی جسم سے غیر ضروری مادوں کے اخراج کا نظام بھی اپنی ذات میں ایک مکمل نظام ہے.یقیناً یہاں بھی اصول عدل کا رفرما ہے جبکہ انسان کو اس کا کچھ بھی علم نہیں جسے قدرت نے غذا کے مفید
حصہ کو ہضم کرنے کے بعد زہریلے مادوں کو باہر نکالنے کا یہ شاندار نظام عطا کر رکھا ہے.ایک انسان
اپنے دانتوں کے ساتھ نا انصافی کرتا ہے اور نتیجہ انہیں خراب کر لیتا یا کھو دیتا ہے تب اسے اپنی حماقت
کا احساس ہوتا ہے کیونکہ کھانے میں بے اعتدالی اور اسراف نہ صرف دانتوں بلکہ نظام انہضام اور
نظام اخراج دونوں کیلئے بیک وقت نقصان دہ ہوتا ہے اور ذیا بیطیس کی بعض اقسام کی وجہ بنتا ہے.لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان کو غذا کی ان بے اعتدالیوں سے نمٹنے کیلئے کئی ایک دفاعی نظام بھی عطا
کئے گئے ہیں.بات کو مزید کھولنے کیلئے ہم ذیا بیطس کی مثال پر مزید غور کرتے ہیں.ذیا بیطس ایک عام سی
بیماری ہے لیکن دراصل یہ محض ایک بیماری نہیں بلکہ اب تک اس کی سینکڑوں اقسام دریافت کی جاچکی
ہیں اور ان میں سے تقریباً ہر ایک کے خلاف جسم کو اندرونی دفاعی قو تیں بھی دی گئی ہیں.اس کی بعض
اقسام غدودوں مثلاً لبلبہ کی خرابی سے پیدا ہوتی ہیں.لبلبہ دو قسم کی رطوبتیں پیدا کرتا ہے جن میں سے ایک انسولین کہلاتی ہے.انسانی جسم کے تمام
خلیات کو اپنی بقا کیلئے مسلسل توانائی کی ضرورت رہتی ہے.انسولین کا کام شکر کو ہضم کر کے یہ توانائی
ان خلیات تک پہنچانا ہے.اگر انسان شکر نہ بھی کھائے تو جو نشاستہ دار غذائیں وہ مختلف شکلوں میں
استعمال کر رہا ہوتا ہے وہ شکر میں تبدیل ہوتی جاتی ہیں اور اگر انسولین ضرورت سے زیادہ مقدار میں
پیدا ہونی شروع ہو جائے تو وہ ہائپوگلیسمیا (HYPOGLYCAEMIA) نامی بیماری کا باعث
بنتی ہے جس کی وجہ سے جسم میں شکر کی مقدار اچانک انتہائی خطرناک حد تک گر جاتی ہے اور فوری طبی
امداد نہ ملنے کی صورت میں اچانک موت واقع ہو سکتی ہے یا پھر گہری بے ہوشی کی وجہ سے دماغ کے
خلیات اور دیگر اعضائے رئیسہ کو نقصان پہنچ سکتا ہے.جسم میں انسولین کی پیداوار کو کنٹرول کرنے کیلئے ایک پیچیدہ اطلاعی نظام کام کر رہا ہے جو گویا
ایک الارم بجا کر جسم کو یہ بتا دیتا ہے کہ جس قدر انسولین چاہئے تھی وہ پیدا ہو چکی ہے اب مزید کی
Page 63
انسانی جسم کا اندرونی توازن
51
ضرورت نہیں.انسولین کو بے اثر کرنے والی رطوبت بھی انہیں غدودوں میں پیدا ہو رہی ہوتی ہے
جہاں انسولین پیدا ہوتی ہے.جسم جب یہ رطوبت خارج کرتا ہے تو انسولین کی پیداوار فور ارک جاتی
ہے اور انسان مکمل سیری کی کیفیت محسوس کرتا ہے.تو ازن کسی بھی لحاظ سے بگڑ جائے صحت پر اس
کے بداثرات مترتب ہوں گے.انسولین اور اس کا توازن قائم رکھنے کیلئے قدرت نے جو انتظام کر رکھا ہے اس کی کہانی یہیں ختم
نہیں ہو جاتی.انسولین کے علاوہ بعض دیگر کمیاب عناصر بھی اس پیچیدہ نظام کی معاونت کرتے
ہیں.دراصل خون میں موجود ہر خلیہ کو توانائی درکار ہوتی ہے اور اس توانائی کے استعمال کے بعد
فاضل مادوں کو جسم سے خارج کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے.چنانچہ قدرت نے ایسا انتظام کر رکھا
ہے جس کے ذریعے فاضل اور زہریلے مادے باہر پھینک دیئے جاتے ہیں.مذکورہ بالا تمام افعال خون کی گردش کے ذریعے ہی سرانجام دیئے جاتے ہیں یہ نظام اپنے اندر
بے شمار عجائبات رکھتا ہے لیکن یہ خود کو بھی تباہ کر سکتا ہے.خون میں پائے جانے والے مختلف قسم کے
خلیات جس مائع میں تیرتے ہیں اگر اسے ان خلیات کے اندر آنے دیا جائے تو یہ ان کے نیوکلیس کو
فوری طور پر تباہ کر سکتا ہے.اس ممکنہ خطرہ سے نمٹنے کیلئے ہر خلیہ ایک دُہری تہ دار جھلی میں لپٹا ہوتا ہے
جو اس کیمیائی محلول کو براہ راست خلیہ میں جذب ہونے سے روکتی ہے.یوں یہ دُہرے غلاف والی
جھلی خلئے کو کسی بھی ممکنہ حادثے سے بچاتی ہے.دونوں جھلید دوں میں بعض ایسے مسام پائے جاتے
ہیں جن میں سے شکر کا مالیکیول اور اس سے جڑا ہوا انسولین کا مالیکیول گزر کر خلئے کے مرکز تک جا
پہنچتا ہے جہاں اسے فوراً ہی استعمال کر لیا جاتا ہے.فاضل مادے انہی جھلیوں کے مساموں کے
ذریعے واپس خون میں شامل ہو جاتے ہیں جو پھر جلد پر پسینے کی صورت میں یا گردوں وغیرہ کی انتہائی
پیچیدہ لعاب دار جھلیوں کے ذریعے خارج کر دیئے جاتے ہیں.خلئے میں شکر کا انجذاب اور فاضل
مادوں کا اخراج نا قابل یقین تیز رفتاری سے ہوتا ہے.یہ توانائی کی نقل و حمل کا نظام ہے لیکن اسی پر بس نہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے.انسانی جسم کے ہر عضو کو بشمول ان خلیات کے جو خون میں موجود ہیں اپنی بقا کیلئے ایک معین مقدار میں
شکر کی ضرورت ہوتی ہے لیکن ظاہر ہے کہ یہاں بھی ترجیحات مقرر ہیں.دماغ کو دیگر تمام جسمانی
اعضا پر ایک فوقیت حاصل ہے.اگر خون میں شکر کی سطح گر بھی جائے تو دماغ کو کسی نہ کسی طرح شکر کی
مسلسل فراهمی از بس ضروری ہے تاوقتیکہ جسم میں شکر کا ذخیرہ ختم نہ ہو جائے.چنانچہ اگر انسانی جسم
Page 64
52
عدل، احسان اور ایتاء ذي القربى - حصه اول
کے تمام اعضا یکساں مقدار میں شکر استعمال کر سکتے تو کسی اور جگہ زیادہ کھپت کی وجہ سے دماغ کو شکر
کی فراہمی کا سلسلہ رک جانے کا خطرہ ہمیشہ لاحق رہتا.پس ترجیحات کے مابین توازن قائم رکھنے
کیلئے جسم میں ایسے غدود موجود ہیں جو دماغ کے علاوہ ہر عضو میں شکر کا استعمال روکنے کیلئے ایک خاص
قسم کی رطوبت پیدا کرتے ہیں.انسانی جسم میں یہ توازن محض ایک جگہ پر ہی نہیں پایا جا تا بلکہ نہایت بار یک در بار یک بے شمار
توازن پیدا کئے گئے ہیں اور پھر انہیں قائم بھی رکھا جاتا ہے.یہ وہ کامل عدل ہے جو انسانی زندگی کی
مختلف سطحوں پر لاشعوری طور پر مصروف عمل ہے.اسے اگر کامل عدل نہ بھی کہا جائے تب بھی اس
حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ عدل اور کامل توازن ایک ہی مظہر فطرت کے دو نام ہیں.بالفاظ
دیگر ہم بلا خوف تردید یہ کہ سکتے ہیں کہ کامل صحت دراصل کامل عدل کا ہی دوسرا نام ہے.انسانی جسم میں شکر کے توازن کے مسئلہ کو بخوبی سمجھنے کیلئے ایک معین مثال پر غور کریں کہ انسانی
جسم کو کس قدر شکر کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کی کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ سطح کیا ہے.خون کے
ہر 100 ملی لٹر میں کم از کم 60 ملی گرام شکر درکار ہوتی ہے.اس مساوات کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ شکر کی
ی سطح 100 ملی لٹر خون میں 180 ملی گرام سے نہیں بڑھنی چاہئے.(5) اگر یہ اس سے بڑھ جائے تو اس
غیر متوازن حالت کو بلڈ شوگر کہا جاتا ہے.اگر انسولین کے ذریعے یہ توازن قائم نہ رہے تو ضرورت سے زیادہ شکر کو گردوں کے ذریعے
جسم سے باہر نکال دیا جاتا ہے تاکہ یہ زائد شکر جسم کی خلیاتی بافتوں کو گلا کر ختم نہ کرنا شروع کر دے.جب یہ زائد شکر پیشاب کے رستے جسم سے خارج ہونا شروع ہو جائے تو یہ ذیا بیٹس کی وہ قسم ہے
جس میں پیشاب میں شکر کی زائد مقدار پائی جاتی ہے.بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ گردے بھی
اس شکر کو نکالنے میں کامیاب نہیں ہو پاتے جس کی وجہ سے خون میں شکر کی سطح خطر ناک حد تک بلند
ہو جاتی ہے جس سے بعض اعضا کو سخت نقصان پہنچتا ہے.جس طرح تیز اب کسی چیز کو گلا دیتا ہے اسی
طرح خون میں شکر کی زائد مقدار سے دل کے والو گل کر ناکارہ ہو جاتے ہیں.عروق شعری میں
جہاں خون کے بہاؤ کی رفتار بہت ست ہوتی ہے یہ زائد از ضرورت شکر جم کر کئی قسم کی بیماریوں اور
نقصانات کا پیش خیمہ بنتی ہے.چنانچہ اگر آنکھوں کی عروق شعریہ یعنی باریک رگوں میں ایسا ہو تو سفید
یا کالاموتیا اور آنکھ کی دیگر بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں.یہ پیغام رساں اعصاب کی کا ہلی اور سست روی
کا باعث بھی بن سکتا ہے جس کا براہ راست نتیجہ دیگر خطرات کے ساتھ ساتھ ان پیغامات کی ترسیل
Page 65
انسانی جسم کا اندرونی توازن
53
میں سست روی بھی ہوتا ہے جو اعصاب کے ذریعہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچائے جاتے ہیں.روزمرہ کے تجربات میں ہم دیکھتے ہیں کہ ذیا بیطس کے بعض مریض اس در دکو محسوس نہیں کر سکتے
جو دل کے کھچاؤ کی وجہ سے ہوتا ہے.چنانچہ خطرہ کی ان گھنٹیوں پر توجہ نہ دینے کی وجہ سے انہیں
اچانک دل کا دورہ بھی پڑسکتا ہے.پس عدل کے توازن
کی باتیں کرنا محض ایک علمی لذت کا حصول
نہیں ہے.کارخانہ قدرت میں عدل کے مستقل فقدان یا اس کے عدم توازن کی بالعموم سزا ملتی ہے.افسوس! که انسان اس سبق کو یکسر نظر انداز کر دیتا ہے اور اس دھو کے میں مبتلا رہتا ہے کہ وہ عدل کو قائم
ند رکھ کر بھی اس کے بدنتائج سے بچ سکتا ہے.اس موضوع پر ہم آئندہ صفحات میں بات کریں گے.بیماری کے خلاف حفاظتی تدابیر:
اب ہم تو ازن کی بعض اور مثالوں کو لیتے ہیں جو ایک صحت مند زندگی کے قیام کیلئے اللہ ہ
نے پیدا فرمایا ہے.صرف انسان ہی نہیں بلکہ دیگر بے شمار انواع حیات بھی اسی محکم اور غیر متبدل
اصول توازن کے تابع ہیں.چنانچہ جہاں کہیں دانستہ یا نادانستہ اس قانون کی خلاف ورزی ہوگی
و ہیں بیماری ضرور نمودار ہوگی.اللہ تعالیٰ نے احسانِ عظیم کے طور پر انسانی جسم کو ایسا نظام بھی عطا کر رکھا ہے جو اسے مختلف
صدمات سے بچاتا اور اس کی حفاظت کرتا ہے.یہ نظام صرف عدل کے دائرہ سے ہی تعلق نہیں رکھتا
بلکہ ایک زائد انعام ہے جو بغیر کسی محنت کے خاص رحمت سے اسے عطا ہوا ہے.ایک اور زاویے سے
دیکھا جائے تو کہا جاسکتا ہے کہ انسانی کمزوریوں، حد سے زیادہ غفلت اور حادثات کو دیکھتے ہوئے
اللہ تعالیٰ نے تلافی کا ایک مکمل نظام اسے فراہم کر رکھا ہے.انسان کے شعوری نقطہ نگاہ سے دیکھا
جائے تو اس میں احسان زیادہ کارفرم دکھائی دیتا ہے جس پر قبل از میں کسی حد تک بحث گزرچکی ہے.احسان اور ایتا ء ذی القربی کے ذریعے جو کچھ انسان کو ملتا ہے وہ عدل سے بلند تر ہے.مثلاً اگر
انسان کو اس کی روز مرہ کی غذائی ضروریات کیلئے غذا کو ہضم کرنے والی رطوبتیں فراہم کر دی جاتیں تو
اس کا مطلب یہ تھا کہ ہر جاندار صرف اتنا ہی کھا سکتا جتنی ضرورت ہوتی.اس صورت میں اس کیلئے
زائداز ضرورت کھا سکنے کی کوئی گنجائش نہ ہوتی.لیکن اللہ تعالیٰ نے جانداروں کے ساتھ انتہائی احسان کا
یہ سلوک فرمایا ہے کہ زائد از ضرورت جو غذا بھی وہ استعمال کرتے ہیں وہ چربی کی صورت میں محفوظ ہو
جاتی ہے جو خوراک کی قلت کے وقت اس کی زندگی کو قائم رکھنے کے کام آتی ہے.اس میں کوئی شک
نہیں کہ ضرورت سے زیادہ چربی ایک بوجھ ہے لیکن ہر جاندار کو اپنی بقا کیلئے مناسب مقدار میں چربی
Page 66
54
عدل، احسان اور ایتاء ذي القربى - حصه اول
کی ضرورت ہوتی ہے.عام طور پر ہر جاندار اس سے دو گناغذا ہضم کر سکتا ہے جتنی ایک صحت مند زندگی
کیلئے مطلوب ہے لیکن جب وہ اس حد سے بھی تجاوز کرتا ہے تو سزا کا دائرہ شروع ہو جاتا ہے.یہ
ناممکن ہے کہ وہ قوانین عدل توڑنے کا عادی بھی ہو اور اسے اس کے نتائج بھی نہ بھگتنا پڑیں.توازن قائم رکھنے والے اس نہایت لطیف نظام کے بارہ میں ہمارا علم ابھی تک نا کافی ہے.لیکن
افسوس! انسان کتنا بد قسمت ہے کہ حیاتیاتی ارتقا کا نقطہ عروج ہونے اور سوچنے سمجھنے کی بہترین
صلاحیتوں سے نوازے جانے پر وہ بجائے خدا تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بننے کے اکثر رعونت کا شکار ہو
جاتا ہے.عادلانہ سلوک روا ر کھنے والے خالق کے ساتھ اس کا رویہ کس قدر غیر عادلانہ ہے.حقیقت
یہ ہے کہ باہم مربوط لا تعداد عوامل کی ایک وسیع اندرونی کائنات ہے جو ایک حسین اور کامل توازن کے
ساتھ تمام ضروریات زندگی کا ہر پہلو سے احاطہ کئے ہوئے ہے.انسان کے اندر پایا جانے والا یہ حسین
توازن اور کامل ہم آہنگی ایک اعلیٰ درجہ کی موسیقی کی مانند ہے.انسان تخلیق خداوندی کا سب سے بڑا
شاہکار ہے لیکن ان عجائبات سے کتنا بے خبر ہے جو اس کے اندر موجود ہیں.انسولین کی پیداوار میں احسان کا کردار:
اس نکتہ کی مزید وضاحت کیلئے ہم ہر جانور کو در کارشکر کی روزمرہ ضروریات والی مثال پر دوبارہ
غور کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح خدا تعالیٰ کا احسان بسیار خوری کے بداثرات سے مریض کو
بچاتا ہے.مثلاً اگر لبلبہ سے پیدا ہونے والی انسولین صرف روزانہ کی شکر کی ضرورت کے عین مطابق
ہوتی تو ظاہر ہے کہ یہ محض روزانہ کی ضرورت پوری کرنے کیلئے کافی ہوتی.اس صورت میں احسان کا
کوئی بھی کردار نہ ہوتا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو روزمرہ ضروریات سے زیادہ مقدار میں انسولین پیدا
کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے.چنانچہ اگر ایک صحت مند انسان ضرورت سے کئی گنا زائد شکر
استعمال کر بیٹھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے احسان کا سلوک اسے اس کے بدنتائج سے محفوظ رکھے گا.دلچسپ امر یہ بھی ہے کہ اگر لبلبہ کسی خرابی کے باعث مطلو به انسولین کا 1/7 حصہ بھی پیدا کر رہا
ہو، تو یہ تھوڑی سی مقدار بھی روزمرہ کی ضروریات کو بآسانی پورا کرنے کیلئے کافی ہوتی ہے.ان
سائنسی مظاہر کی باریکیوں کو نہ سمجھنے والے ایک عام آدمی کیلئے اس امر کی مزید وضاحت مفید ہوگی.انسولین کا پیدا ہونا کسی بھی طرح کوئی اتفاقی امر نہیں ہے.جانوروں کو اپنی ضروریات کا کچھ بھی
علم نہیں ، بس کھانے کی ایک شدید طلب ہے جو انہیں ہر ایسی چیز کھانے پر مجبور کرتی ہے جس سے ان
کی بھوک مٹ سکے اور وہ خوش ذائقہ بھی ہو.لیکن اس کے باوجود ایک خاص مقام پر پہنچ کر انہیں
Page 67
انسانی جسم کا اندرونی توازن
55
اندرونی طور پر یہ تنبیہ ہو جاتی ہے کہ اب کھانے سے ہاتھ روک لینا چاہئے.اگر ایسا نہ ہوتا تو دنیا کا
ایک بڑا حصہ بھوک سے مرجاتا کیونکہ بسیار خور دوسروں کیلئے کچھ بھی نہ چھوڑتے.عام صحت مند جانوروں میں بھی انسولین کی پیداوار میں کمی بیشی با قاعدہ ایک منظم طریق پر
ہوتی ہے.حالت آرام میں ایک جانور کو بہت کم انسولین درکار ہوتی ہے لیکن جب اچانک وہ متحرک
اور فعال ہوتا ہے تو اسی نسبت سے انسولین کی پیداوار بڑھنے لگتی ہے.اگر یہ نہ ہو تو کھیلوں اور ورزشی
مقابلہ جات میں کسی اعلیٰ معیار کا حاصل کرنا ناممکن ہو جائے بالخصوص اولمپک مقابلوں میں حصہ لینے
والے اکثر کھلاڑی تمغہ وصول کرنے سے پہلے ہی اچانک موت کا شکار ہو جائیں گے.اگر جسم تو انا ہے اور اسے متوازن غذامل رہی ہے تو فضلات کے اخراج کی خاطر گردوں کو اپنا
کام سرانجام دینے کیلئے مقررہ وزن اور حجم میں ہونا ضروی ہے.لیکن گردوں میں فضلات کے اخراج
کی صلاحیت روزمرہ ضرورت سے کہیں زیادہ ہوتی ہے کیونکہ معمول کا کام سرانجام دینے کیلئے ایک
گردے کا آٹھواں حصہ ہی کافی ہوتا ہے.اچانک لاحق ہونے والی بیماری یا خوش خوراک لوگوں کی
بے اعتدالیوں کے باعث اسے کسی اضافی سہارے کی قطعاً ضرورت نہیں ہوتی.یہاں احسان اور
ایتاء ذی القربیٰ اپنے پورے حسن کے ساتھ کارفرما دکھائی دیتے ہیں.اگر انسان اپنے گردوں سے انصاف نہ کرے یعنی عدل سے کام نہ لے اور احسان الہی کو بھی
مسلسل نظر انداز کرتا چلا جائے حتی کہ گردہ کا7/8 حصہ کھو بیٹھے، تب بھی وہ ایک صحت مند شخص کی طرح
بقیہ زندگی گزار سکتا ہے بشرطیکہ وہ اس نقصان سے سبق سیکھ کر متوازن غذا کا استعمال شروع کر دے.چنا نچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر صورتوں میں عدل اور احسان ایک دوسرے کے عمل میں دخل دیئے
بغیر ا کٹھے پنپ سکتے ہیں.تاہم اگر ان دونوں میں ٹکراؤ کا اندیشہ ہو تو احسان کے عمل کو روک دیا جاتا
ہے اور عدل جاری و ساری رہتا ہے خصوصاً جب احسان عدل
کو قربان کرنے کا متقاضی ہو یعنی جب
احسان کرنے کیلئے عدل کو ہاتھ سے دینا پڑے.جہاں تک احسان، عدل کے ساتھ ساتھ رہ سکتا ہے
اسے اپنا کام کرنے کی اجازت ہے.اگر چہ احسان کا مرتبہ بہت بلند ہے لیکن عدل زیادہ بنیادی
حیثیت رکھتا ہے اور بنیادی اشیاء کو اضافی اور اختیاری اشیاء پر کسی صورت بھی قربان نہیں کیا جاتا.اسی تعلق میں ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
اَلْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِى مِعَى وَاحِدٍ وَّ الْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ امْعَاءٍ.ترجمہ: مومن تو ایک آنت سے کھاتا ہے جبکہ کافرسات آنتوں سے کھاتا
ہے.(6)
Page 68
56
عدل، احسان اور ایتاء ذي القربى - حصه اوّل
یہ حدیث نظام انہضام کی کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ گنجائش کی خوب وضاحت کر رہی ہے.انسولین کی عدم فراہمی کے علاوہ بھی ذیا بیٹی کی سینکڑوں دیگر وجوہات ہوسکتی ہیں.پس لبلبہ
کے ٹھیک کام کرنے کے باوجود بھی کسی کو ذیا بیطیس کا مرض لاحق ہو جانا عین ممکن ہے.سائنسدان اب
تک ایسے کئی عوامل دریافت کر چکے ہیں جو خون میں شکر کے انجذاب کے پیچیدہ نظام کو قائم رکھنے
میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں.تاہم آخری نتیجہ ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ مکمل متوازن غذا یا بالفاظ دیگر عدل
پر زور دیا جاتا ہے.کیلشیم:
کیلشیم بھی جانوروں کو صحت مند رکھنے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے.اگر کیلشیم کا توازن
معمولی سا بھی بگڑ جائے تو ان کی صحت کو شدید خطرہ لاحق ہو سکتا ہے.انسانی صحت کے حوالے سے
کیلشیم کے توازن میں معمولی سا بگاڑ گلوکوز کی سطح میں عدم توازن سے پیدا ہونے والے خطرات سے
کہیں زیادہ مضر ثابت ہوتا ہے بلکہ بعض اوقات اچانک موت کا باعث بھی بن جایا کرتا ہے.مویشیوں میں پائی جانے والی ایک عام سی بیماری اس امر کی بخوبی وضاحت کرتی ہے کہ کیلشیم کا مقررہ
تناسب میں ہونا جسم کیلئے کس قدر ضروری ہے.بعض اوقات وائرس یا ماحولیاتی عوامل کے باعث ،مویشیوں میں توانائی کی اچانک کمی ظاہر ہونا
شروع ہو جاتی ہے جو کسان کیلئے بہت تشویش کا باعث ہو جاتی ہے کیونکہ اس کی بظاہر کوئی وجہ دکھائی
نہیں دے رہی ہوتی.مثلاً ایک گائے جو ایک رات پہلے بالکل تندرست تھی اچانک بے جان سی ہو کر
گھٹنوں کے بل ایسے گرتی ہے کہ دوبارہ اُٹھ نہیں پاتی.بخار یا کسی اور بیماری کی کوئی ظاہری علامت
بھی موجود نہیں ہوتی اور جانور موت کے منہ میں جارہا ہوتا ہے.ایک قابل ڈاکٹر ، جلد حل ہو جانے والی
کیلشیم کا ٹیکہ لگا کر یقینا اسے بچا سکتا ہے.یوں لگتا ہے جیسے معجزانہ طور پر اس میں دوبارہ جان پڑ گئی ہو.اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کیلشیم کا اپنی مطلوبہ سطح کو برقرار رکھنا کس قد راہم بات ہے.ایک صحت مند
انسان کو کیلشیم کی کم سے کم 2.9 فیصد اور زیادہ سے زیادہ 4.10 فیصد مقدار کی ضرورت ہوتی ہے.(7)
بعض اوقات کیلشیم کی سطح میں کمی بھی انسانوں میں مسلسل بڑھتی ہوئی کمزوری کا باعث بن جایا
کرتی ہے.اب تک اس
کو سمجھنے کیلئے جو اصول ہمارے علم میں آیا ہے وہ یہ ہے
کہ کیلشیم کی سطح میں کسی
قسم کا کوئی بگاڑ پیدا نہیں ہونا چاہئے کیونکہ یہ انسانی صحت کیلئے انتہائی خطرناک ہوتا ہے.اس پر کام
کرنے والے سائنسدانوں کی کئی نسلیں بھی اس لطیف توازن کو برقرار رکھنے والے تمام ذمہ دار عوامل
Page 69
انسانی جسم کا اندرونی توازن
کو شاید مکمل طور پر نہ سمجھ سکیں.57
انسانی جسم کی ساخت میں کیلشیم کا کردار انتہائی پیچیدہ ہے.کیلشیم فاسفیٹ انسانی ڈھانچے کو
مضبوطی اور سختی عطا کرتی ہے جبکہ کیلشیم کے نمکیات ہڈیوں اور دانتوں کو مضبوط بنانے کے ساتھ ساتھ
خلئے کے اردگرد موجود جھلی نما بافتوں کو بھی مضبوط کرتے ہیں.چنانچہ خلیات اور دانتوں کی خستگی نیز
طبیعت کا حد سے بڑھا ہوا چڑ چڑا پن، کیلشیم کی کمی کی علامات ہیں جبکہ کیلشیم کی زیادتی کا نتیجہ ذہنی
الجھنوں اور جسمانی کاہلی کی صورت میں سامنے آتا ہے.خلئے کے اندر زندہ پروٹوپلازم ہوتا ہے جس کے گرد ایک مضبوط جھلی پائی جاتی ہے.کیلشیم کی کمی
کے باعث یہ جھلی اپنی مضبوطی کھو کر خلئے کی کمزوری کا باعث بنتی ہے جس کے نتیجے میں خلئے سے باہر
پروٹو پلازم کے ابھار بن سکتے ہیں.انسانوں میں کیلشیم کی کمی بیشی ان کی غذا اور ماحول کے مطابق
ہوتی ہے چنانچہ اس کی کمی یا زیادتی سے ان کی زندگی کئی قسم کی بیماریوں کا شکار ہوسکتی ہے نیز ہڈیوں
کے ریشوں اور خون میں کیلشیم کا عدم توازن مندرجہ ذیل بیماریوں
کا پیش خیمہ ثابت ہوا کرتا ہے.---ویسوڈیلیشن (VASODILATION): جس کے نتیجہ میں بلڈ پریشر گر
جاتا ہے،
یا...دل کے عضلات میں سکڑنے کی طاقت کا کم ہو جانا،
--- ہڈیوں کی بافت میں ایسی تبدیلی جس کے نتیجے میں وہ بھر بھری ہو کر سوکھ جاتی ہیں،
--- تشویشناک آسٹیور تھریٹس (OSTEOARTHRITIS): جس میں
کیلشیم کا تناسب بگڑ جاتا ہے اور انجائنا کے حملے بھی ہوتے ہیں.کیلشم کی یہ کمی بلڈ پریشر میں کمی کے
باعث ہوتی ہے جو دماغ کے خلیوں
اور دیگر بافتوں میں شدید اور مستقل خرابی کا سبب بن سکتی ہے.چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم کو ایک اور حفاظتی نظام فراہم کر رکھا ہے جو کیلشیم کا توازن بگڑنے
نہیں دیتا کیلشیم کے لطیف توازن کو برقرار رکھنے کے ذمہ دار عوامل لا تعداد ہیں اور انتہائی پیچیدہ طور
پر باہم مربوط بھی ہیں.اس نگران اور اصلاحی نظام کا سورۃ الشمس کی آیت نمبر 9 کے ساتھ ایک گہرا
تعلق ہے.اس تناظر میں تقویٰ سے مراد یہ ہوگی کہ ہم نے زندگی کے تعمیری مادے میں خطرات کی
نشان دہی کر دی ہے اور ان سے بچاؤ کے متعلق تمام تفصیلی ہدایات لکھ چھوڑی ہیں.چنانچہ کیلشیم کے
تناسب پر نظر رکھتے ہوئے بر وقت ضروری اقدام کرنے والے کئی نظام جسم میں طبعی طور پر موجود
ہیں.بوقت ضرورت پیچیدہ غدودی نظام فوراً حرکت میں آتا ہے جس میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ
Page 70
58
عدل، احسان اور ایتاء ذي القربى - حصه اول
وہ سب کچھ فراہم کر سکے جو جسم کو درکار ہے.خون اور نرم بافتوں کو کیلشیم کی تھوڑی سی مقدار درکار ہوتی ہے جبکہ بقیہ مقدار دانتوں اور ہڈیوں
میں ذخیرہ ہو جاتی ہے.جب خون میں کیلشیم کی کمی واقع ہوتو اسے اس ذخیرے سے پورا کیا جاتا
ہے.غذا میں کیلشیم کی مقدار کے لحاظ سے جسم اس کے انجذاب کی شرح میں
کمی بیشی کرتارہتا ہے.اگر
غذا میں کیلشیم کم ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جسم مقررہ مقدار سے زیادہ کیلشیم جذب کر رہا ہے اور اگر
کیلشیم زیادہ مقدار میں کھائی جارہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زائد کیلشیم ہڈیوں میں ذخیرہ ہوتی
رہے گی یہاں تک کہ یہ اپنی بلند ترین ممکنہ سطح تک پہنچ جائے تب آنتوں کے ذریعہ کیلشیم کے جذب
ہونے کی شرح کم ہو جاتی ہے.وٹامن ڈی کی موجودگی جسم میں کیلشیم کے انجذاب کو بڑھا دیتی ہے.لہذا منطقہ حارہ کے ممالک میں، جہاں خواہ غذا میں کیلشیم کی مقدار کم بھی ہو جسم پر زیادہ دھوپ پڑنے
سے پیدا ہونے والے وٹامن ڈی کی وجہ سے کیلشیم کے جذب ہونے کی شرح بہت بڑھ جاتی ہے.پیراتھائرائڈ (PARATHAYROID) غدود میں پیدا ہونے والا پیرا تھورمون
(PARATHORMONE) نامی ہارمون کیلشیم کے توازن میں با قاعدگی کا ذمہ دار ہوتا ہے.یہ وٹامن ڈی کے ساتھ مل کر جسمانی ضرورت کے مطابق کیلشیم کے انجذاب میں کمی بیشی کا کام کرتا
ہے.اس طرح کیلستون (CALCITONE) نامی ایک اور ہارمون بھی کیلشیم کے توازن کو
با قاعدہ بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے.جب خون میں کیلشیم کی مقدار بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو
کیلسٹون زائد کیلشیم کو ہڈیوں میں واپس بھیج دیتا ہے علاوہ ازیں آنتوں کے ذریعہ جذب ہونے والی
کیلشیم کوبھی گھٹا دیتا ہے.سوڈیم اور پوٹاشیم :
اب ہم ایک اور پہلو سے فجور اور تقویٰ کے نظام کی وضاحت کرتے ہیں.سوڈیم اور پوٹاشیم دو
ایسے عناصر ہیں جو زندگی کی بقا کیلئے نہایت ضروری ہیں.ان دونوں کے مابین ایک توازن کا ہونا
از حد ضروری ہے.تاہم پورے انسانی جسم میں دونوں کا تناسب یکساں نہیں ہوتا بلکہ مختلف حصوں
میں مختلف ہوتا ہے.مثلاً ہڈیوں اور گوشت میں پوٹاشیم کی مقدار سوڈیم سے زیادہ ہونی چاہئے جبکہ
خون میں سوڈیم کی مقدار پوٹاشیم سے زیادہ.ان نمکیات میں عدم توازن خطرناک نتائج کا حامل ہو
سکتا ہے.لہذا جسم کے مختلف حصوں میں ان دونوں کے مابین توازن کو برقرار رکھنا کوئی اتفاقی امر
نہیں
بلکہ ایک نہایت منظم منصوبہ بندی کا نتیجہ ہے.
Page 71
انسانی جسم کا اندرونی توازن
59
اسی طرح اعصابی نظام کی صحت کا انحصار کافی حد تک سوڈیم اور پوٹاشیم دونوں پر ہے لیکن
اعصاب میں ان کی ضرورت حالات کے مطابق بدلتی رہتی ہے.کوئی بھی پیغام ایک زنجیر کی صورت
میں ایک سے دوسرے خلئے تک آگے سے آگے پہنچایا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ جسم کے اس حصے تک
پہنچتا ہے جہاں اس کا پہنچایا جانا مقصود ہوتا ہے.پیغامات کی ایک سے دوسرے خلئے تک ترسیل کے
دوران سوڈیم خلیات کے اندر جاتی جبکہ پوٹاشیم خلیات کے اندر سے باہر آتی ہے.اب اگر اس کے
فوراًبعد اس عمل کا رخ نہ پلٹا جائے اور پوٹاشیم کی سطح کو دوبارہ جلد معمول پر نہ لایا جائے تو اچانک
موت واقع ہو جائے گی.اس سے ہم سورۃ الانفطار کی آٹھویں آیت میں استعمال کی گئی قرآنی بیان ” فَسَونَكَ فَعَدَ لَكَ“
کا مطلب اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں.گویا یہ چھوٹا سا فقرہ ہمارے بدن میں موجود ہر قسم کے توازن
کے سارے پیچیدہ نظام کا خلاصہ ہے.خلیات کی تقسیم کا عمل :
انسانی جسم میں خلیات کی تقسیم کا عمل بھی بہت دلچسپ ہے.ہر سات سال کے اندر انسانی جسم
کے تمام خلیات کیٹا بولزم (CATABOLISM) جیسے انتہائی پیچیدہ نظام کے تحت تبدیل ہو
جاتے ہیں.عمل تعمیر کے تحت خلیات کی تعمیر اور تخریب کا عمل مسلسل جاری رہتا ہے لیکن ہمیں محسوس
نہیں ہو رہا ہوتا کیونکہ اس سے جسمانی خدو خال میں کوئی بنیادی تبدیلی واقع نہیں ہوتی.یہ تو ممکن ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ کسی کی صحت اچھی ہو جائے اور وزن بھی بڑھ جائے یا پھر
صحت بگڑ جائے اور گوشت پوست کم ہو جائے لیکن جسمانی ساخت بعینہ قائم رہتی ہے.کیونکہ عمل تعمیر
کے نتیجے میں پیدا ہونے والا ہر نیا خلیہ جو مرنے والے خلئے کی جگہ لے رہا ہوتا ہے، اپنے پیش رو کی
ہو بہو تصویر ہوتا ہے.اس کی مزید وضاحت کیلئے سب سے زیادہ معروف مثال انگلیوں کے نقوش کی ہے.چنانچہ
ایک نومولود کے انگوٹھے کا نقش اس کے بوڑھا ہونے تک اپنی تمام تر تفاصیل کے اعتبار سے بعینہ قائم
رہتا ہے.اس مضمون کا تعلق انسانی جسم میں جاری نظام عدل کے ساتھ ہے.جسمانی اعضاء کومسلسل
نئے خلیات کی ضرورت رہتی ہے.اگر یہ نئے خلیات پیدا نہ ہوں تو اعضاء ختم ہو جائیں لیکن اگر نئے
خلیات کی فراہمی ضرورت سے زیادہ ہو جائے تو اعضاء کا حجم بڑھتا چلا جائے گا.اگر یہ فراہمی
ضرورت سے کم ہو تو اعضاء سکڑنے لگ جائیں گے.اگر اپنی عمر پوری کر چکنے والے خلیات کی جگہ
Page 72
60
عدل، احسان اور ایتاء ذي القربى - حصه اول
اتنے ہی نئے خلیات پیدا نہ ہوں تو ایک عدم توازن پیدا ہو جائے گا.اس اصول کا اعضاء پر اطلاق
کر کے دیکھا جائے تو اس کے نتائج بآسانی سمجھ آسکتے ہیں.آنکھ کی ہی مثال لے لیں.آنکھ جو افعال سرانجام دیتی ہے ان کے دوران آنکھ کے ہر حصہ میں
خلیات مسلسل استعمال ہو رہے ہوتے ہیں.اب اگر نئے بننے والے خلیات کی تعدا د مرنے والے
خلیات سے زیادہ ہو جائے تو آنکھیں بڑی ہو کر باہر نکل آئیں گی اور اگر اس توازن کا پلڑا دوسری
طرف جھک جائے تو آنکھ کی جسامت کم ہوتے ہوتے پہلے تو ایک نقطہ کے برابر رہ جائے گی اور پھر
بالکل ہی معدوم ہو جائے گی.مختصر یہ کہ اگر جسم کے کسی بھی عضو کا توازن بگڑ جائے تو یا تو یہ بہت ہی بڑا
ہو جائے گا یا پھر بکلی فنا ہو جائے گا.عالم حشرات پر ایک نظر:
اگر چہ اب تک بعض ترقی یافتہ انواع حیات اور انسان کے جسمانی نظام کی مثالیں دی گئی ہیں
لیکن یادر ہے کہ نظام عدل تمام انواع حیات کا پوری طرح احاطہ کئے ہوئے ہے.حشرات کی دنیا کیلئے بھی نگرانی کا یہ نظام انتہائی اہمیت کا حامل ہے.ہر کیڑے کا ایک مقررہ حجم
ہے جو اگر مسلسل ایک نظام کے تابع نہ رہے تو نا قابل تصور حد تک بگڑ سکتا ہے.حشرات الارض اپنی
زندگی کو برقرار رکھنے کیلئے بعض ایسی مخصوص قسم کی غذائیں کھاتے ہیں جو ان کے مناسب حال ہیں.اگر قوانین قدرت ان کی مسلسل نگرانی نہ کر رہے ہوتے تو ان
کا حجم بڑھ کر سارے کرۂ ارض کے برابر
ہو جاتا.ان کی نشو و نما ایک مخصوص مقام تک پہنچ کر کیوں رک جاتی ہے؟ ایسی کون سی طاقتیں ہیں
جنہوں نے یہ حدود متعین کر رکھی ہیں؟ ایسا کون سا نظام ہے جو ان کی نشو ونما کو ایک حد کے اندر رکھتا
ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کو اچھی طرح سمجھ لینا ضروری ہے.ان جانداروں کو بلا روک ٹوک بڑھنے
دینا بظاہران کے ساتھ رحم کا سلوک دکھائی دیتا ہے.لیکن سوال یہ ہے کہ کیا دیگر تمام انواع حیات کو
قربان کر کے انہیں بڑھنے دیا جائے؟
پس توازن یا انسانی اصطلاح میں عدل از خود قائم نہیں رہتا بلکہ بعض مخصوص قوتوں کے تابع
اسے کنٹرول کیا جاتا ہے.قبل ازیں ہم نے جسم کے ہر عضو کی نشو ونما کی مثال دی تھی.وہ نظام جو
دانتوں اور آنکھوں وغیرہ کی نشو و نما کو ان مذکورہ بالا جانوروں میں کنٹرول کرتا ہے دراصل تمام
انواع حیات پر حاوی ہے.افسوس کہ انسان بے حد نا شکرا ہے.وہ اپنی تمام تر ذہانت کے باوجود
اس قادر مطلق ہستی سے غافل ہے جس کی گواہی کائنات کا ذرہ ذرہ دے رہا ہے.
Page 73
انسانی جسم کا اندرونی توازن
عدم توازن اور بیماری:
61
اگر انسان اپنی اصل حیثیت پر غور کرے تو اُسے معلوم ہوگا کہ وہ محض ایک مشت خاک ہے.وہ
بلاوجہ اتراتا پھرتا ہے جبکہ وہ کسی بھی چیز کا مالک نہیں ہے.مالک حقیقی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی
کی ذات ہے.انسان
کو ایسا کامل جسمانی وجود بخشا گیا ہے کہ صحت کی حالت میں وہ یہ سمجھنے سے قاصر
رہتا ہے کہ اس کا یہ وجود نہایت عظیم اور باریک در بار یک نظام ہائے توازن کا مرہون منت ہے.لیکن جب وہ بیمار پڑتا ہے تو اس کی بے آرامی ، درد اور تکلیف اس پر اس کی کمزوری اور بے بسی کو
آشکار کر دیتی ہے.تب کہیں جا کر اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے وجود کا اصل سہارا فقط اللہ تعالیٰ کی
ذات ہی ہے اور وہی ہے جو ارد گرد پھیلی ہوئی تمام بیماریوں
کا لقمہ بننے سے انسان کو محفوظ رکھتا ہے.انسان کو ایک ایسے اندرونی خود کار دفاعی نظام کے ذریعے ہر قسم کی بیماری سے بچایا جاتا ہے جو مسلسل
اس کی نگرانی پر مامور ہے.یہاں یہ امر قابل توجہ ہے کہ خواہ جسم کا کوئی چھوٹا سا اور بظاہر غیر اہم دکھائی دینے والا عضو بھی
بیمار پڑ جائے جبکہ باقی سارا جسم بالکل تندرست ہو تب بھی انسان کا پورا وجود اذیت میں مبتلا ہو جاتا
ہے.مثال کے طور پر انگلی کی ایک پور سوجی ہو، دانت میں کیڑا لگا ہو یا آنکھ کے پوٹے میں انفیکشن
ہو تو یہ بھی انسان کیلئے انتہائی تکلیف اور بے چینی کا موجب بن جاتا ہے.اس سے بچنے کیلئے بعض
لوگ خود کشی تک کر لیتے ہیں حالانکہ تکلیف اور بیماری تو صرف ایک چھوٹے سے محدود حصے میں ہوتی
ہے.دماغ میں رسولی بن جائے تو انسان مرگی جیسے موذی مرض میں مبتلا ہو کر نہ صرف خود اذیت کا
شکار ہوتا ہے بلکہ اس کا سارا خاندان اور حلقہ احباب بھی تکلیف اٹھاتا ہے.ایسے مواقع پرہی اللہ تعالیٰ
کے احسانات کی پوری طرح سمجھ آتی ہے.اس کا فضل ہے جو مسلسل ہر ذی روح پر بارش کی طرح
برس رہا ہے.یہ مضامین انہی لوگوں کی سمجھ میں آیا کرتے ہیں جن میں سوچنے سمجھنے اور شکر گزار بندہ
بننے کی صلاحیت پائی جاتی ہے.الغرض تو ازن یعنی عدل کا بگاڑ ہی بیماری کا دوسرا نام ہے.چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض بڑے
بڑے لوگ جنہیں تاریخ کے مختلف ادوار میں عزت و شہرت حاصل تھی، جب بیمار ہوئے تو اپنے
تیمار داروں سے مدد کی بھیک مانگا کرتے تھے جوان کی کسی بھی قسم کی مد کرنے سے قاصر تھے.بڑے
بڑے جابر اور طاقتور بادشاہوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا کہ جب کسی بیماری نے انہیں معذور کر دیا تو
وہ اس قدر بے حیثیت دکھائی دیتے تھے کہ ان کے ادنی ترین غلام بھی اس بات پر تیار نہ ہوتے تھے
Page 74
62
عدل، احسان اور ایتاء ذي القربى - حصه اول
کہ وہ اپنے آقا کی جگہ تخت پر بیٹھ جائیں اور آقاان کی غلامی اختیار کرلے.جولیس سیزر اس کی ایک مثال ہے جو ایک مرتبہ بڑی شاندار اور بارعب تقریر کر رہا تھا کہ اچانک
اس پر مرگی کا حملہ ہوا اور وہ تکلیف کے باعث تڑپنے لگا.اس واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے شیکسپر لکھتا ہے:
” جب اُسے دورہ پڑا تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا،
کہ وہ دیوتا کیسے تڑپتا تھا،
اس کے ہونٹ جو اظہار حق کی جرات نہیں رکھتے تھے، کیسے پھیکے پڑ چکے تھے،
اور وہی آنکھ جس کے اشارہ سے ایک دنیا کا نپتی تھی ، اُجڑ چکی تھی ، اب کس
قدر ویران تھی.“ (Julius Ceaser Act 1 Scene II)
لیکن اس قسم کے واقعات انسان کی انانیت پر کوئی اثر نہیں ڈالتے کیونکہ جیسے ہی وہ صحت کی
طرف لوٹتا ہے تو ذلت اور بے بسی کے ان لمحات کو یکسر بھول کر فورا ہی اپنی جھوٹی انا کا لبادہ دوبارہ
اوڑھ لیتا ہے حالانکہ اگر آپ غور کریں تو مرگی، جو انسان سے اس کا وقار چھین سکتی ہے، درحقیقت
اعصابی نظام کے ایک بالکل معمولی عدم توازن کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے.یہاں تک کہ اکثر
اوقات یقین کرنا بھی ناممکن ہوتا ہے کہ اعصابی نظام کا کون سا حصہ بیمار ہے.-
حفاظت پر مامور فرشتے:
ترقی کی راہوں پر انسان کیلئے جابجا خطرات موجود ہیں.ترقی کی جانب اٹھنے والا ہر غیر محتاط
قدم تباہی کی طرف لے جاسکتا ہے.زندگی اور موت کا عمل بار یک تفاصیل میں جا کر بھی دیکھیں تو
ساتھ ساتھ چلتا ہے.زندگی کی حفاظت کرنے والا نظام اس
قدر گہرا اور اعلیٰ ہے کہ اسے ابھی تک
پوری طرح سمجھا ہی نہیں جاسکا لیکن جو کچھ بھی سمجھ میں آچکا ہے اسے دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے.مذہبی نقطہ نظر کے مطابق ، بظاہر اس خود کار نظام کے پیچھے، ایسی غیر مرئی شعوری طاقتیں کارفرما ہیں
جن کی جہات ہم سے مختلف ہیں اور جنہیں فرشتے کہا جاتا ہے.یہ سارا نظام کا ئنات ایسے قوانین
قدرت کے ذریعے چلایا جا رہا ہے جن کا قیام اور نفاذ بار یک دربار یک تفاصیل میں بھی فرشتوں کے
ذریعے ہوتا ہے.یہاں بھی اسی کا اطلاق ہوتا ہے.مثلاً ترقی کی جانب بڑھتی ہوئی زندگی کی ہرا کائی
کیلئے ہر قدم پر یہ خطرہ موجود ہے کہ اس کا ایک غلط قدم اسے موت کے منہ میں دھکیل سکتا ہے.لیکن
زندگی کی حفاظت پر مامور فرشتے ہر قدم پر اس کی صحیح رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں.ہاں جب موت
کے وقت کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو زندگی کا ہر قدم موت کی جانب اٹھنے لگتا ہے.
Page 75
انسانی جسم کا اندرونی توازن
63
انسان کی بے اعتدالیاں:
اگر انسان کو کھلی چھٹی دے دی جائے تو وہ تمام حدود سے تجاوز کر جاتا ہے.لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا
ایک بہت بڑا احسان ہے کہ جسم کے اندر موجود عظیم کارخانہ کے چلانے میں انسان کا اختیار بہت کم
ہے.وہ نہیں جانتا کہ اس کے اپنے جسم کے اندر کیا کچھ ہورہا ہے اور نہ ہی وہ اپنے اندرونی نظام میں
دخل دے سکتا ہے.زندگی کے لاتعداد افعال انسان کے کسی شعوری عمل کے بغیر ہی جاری وساری
ہیں.یقیناً بعض صورتوں میں انسان
کو اختیار دیا گیا ہے.مثال کے طور پر کھانے پینے میں اسراف،
شہوانی لذات میں محو ہو جانا، طرز زندگی کا پر تعیش ہونا اور بعض دیگر عادات ہیں جن میں انسان کو اپنی
مرضی کا اختیار دیا گیا ہے.چنانچہ انسان ان معاملات میں جو بگاڑ پیدا کرتا ہے اس سے ہم بخوبی
واقف ہیں.وہ اپنے خلاف جو بھی زیادتیاں کرتا ہے، ان کے بدنتائج سے محفوظ رکھنے کیلئے بھی اس
کے اندر ایک باقاعدہ نظام جاری کیا گیا ہے.یہ نظام اسے اس کی بہت سی بے اعتدالیوں اور
زیادتیوں کے نتائج سے بڑی حد تک بچاتا ہے.لیکن اگر انسان مسلسل غلطیاں کرتا چلا جائے یا تمام
حدود سے تجاوز کرتے ہوئے خود کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں ڈال لے تب سزا کا نظام ضرور حرکت
میں آتا ہے.اس کے باوجود صحت اور بیماری، زندگی اور موت کے درمیان ایک طویل کشمکش جاری
رہتی ہے اور قدرت ایسا ہر ممکن انتظام کرتی ہے کہ تخریبی قوتوں کے خلاف یہ جدو جہد طویل عرصہ تک
جاری رہ سکے.مذہبی اصطلاح میں ہم جسے بداخلاقی یا سرکشی کہتے ہیں ہمارے نزدیک اس کا اطلاق در حقیقت
مادی دنیا پر بھی ہوتا ہے.بے شک ہمارا مقصد یہ نہیں کہ مادی اور روحانی امور کے سلسلہ میں ایک
جیسی اصطلاحات کا استعمال کیا جائے لیکن ان کی باہمی مشابہتیں اتنی قوی ہیں کہ انسان کی توجہ خود
بخود ان کی طرف مبذول ہو جاتی ہے.تاہم یہ بات ہر گز نہیں بھولنی چاہئے کہ ایسے انتہائی نازک
مواقع پر بھی اللہ تعالیٰ کا احسانِ عظیم اور اس کی بے پایاں رحمت ہی ہے جو انسان کو بچاسکتی ہے.
Page 76
64
عدل، احسان اور ایتاء ذي القربى - حصه اول
7- عدل سے انحراف
اگر کوئی شخص کھلے ذہن کے ساتھ برائیوں کی اصل جڑ تلاش کرنے کی کوشش کرے تو وہ ہمیشہ اسی
نتیجہ پر پہنچے گا کہ تمام معاشرتی، سیاسی، اقتصادی اور اخلاقی برائیوں کی جڑ دراصل عدل کا فقدان ہی
ہے.پس عدل و انصاف قائم کئے بغیر دنیا امن و آشتی کا گہوارہ بن ہی نہیں سکتی کیونکہ جب نا انصافی اور
جبر و استبداد کا دور دورہ ہو جائے تو بدی جنم لیا کرتی ہے اور دنیا تباہی کے رستہ پر چل نکلتی ہے.اگر انسان حقوق اللہ کی ادائیگی میں عدل سے کام نہیں لیتا تو یہ امر بعید از امکان ہے کہ وہ بنی
نوع انسان کے ساتھ عدل کر سکے.یاد رکھنا چاہئے کہ عدل کے تقاضوں کو صحیح معنوں میں پورا نہ
کرنے کے بدنتائج ضرور بھگتنا پڑتے ہیں.اس قسم کی سزا کا تعلق خدا تعالیٰ کے غضب سے نہیں جو
گویا آسمان سے اترتا ہے بلکہ یہ تو قوانین قدرت کی خلاف ورزی کا فطری نتیجہ ہے کیونکہ کوئی بھی
قوانین قدرت سے بالا نہیں.یہاں بھی رحمت خداوندی ، مغفرت اور احسان کارفرما ہے جس کی وجہ سے انسان کو اس کے ہر گناہ
کی سزا نہیں دی جاتی لیکن جب وہ مقررہ حدود سے تجاوز کر جاتا ہے تو احسان کی ڈھال واپس لے لی
جاتی ہے اور پھر سزا کے عمل میں کوئی روک نہیں رہتی.قرآن کریم اس مضمون کو یوں بیان کرتا ہے:
وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ
كَثِيرٍ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ
اللهِ مِنْ وَلِي وَلَا نَصِيرٍ (الشورى 32,31:42)
ترجمہ: اور تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے تو وہ اس سبب سے ہے جو تمہارے اپنے
ہاتھوں نے کمایا.جبکہ وہ بہت سی باتوں سے درگزر کرتا ہے.اور تم زمین میں
عاجز کرنے والے نہیں بن سکتے اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی سر پرست اور مددگار
نہیں.بالفاظ دیگر انسان اپنے لئے خود ہی مصیبتیں کھڑی کر لیتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کے اکثر گناہ
معاف فرما کر اسے تباہی اور بربادی سے بچاتا ہے.چنانچہ جنگوں کی تاریخ پر غور کرنے سے یہی
ثابت ہوتا ہے کہ نقض امن کی بنیادی وجہ ہمیشہ قوانین عدل کی خلاف ورزی ہوا کرتی ہے.
Page 77
عدل سے انحراف
عقیدہ تثلیث :
65
خدا تعالیٰ کے ساتھ بے انصافی کی ایک نہایت موزوں مثال تثلیث کا عقیدہ ہے.چنانچہ
قرآن کریم فرماتا ہے:
تَكَادُ السَّمُوتُ يَتَفَطَرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ
هَذَا اَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا (مریم 91:19و92)
ترجمہ: قریب ہے کہ آسمان اس سے پھٹ پڑیں اور زمین شق ہو جائے اور
پہاڑ لرزتے ہوئے گر پڑیں کہ انہوں نے رحمن کے لئے بیٹے کا دعویٰ کیا ہے.انسانوں کے مابین جنگ اور بدامنی کی وجوہات پر غور کرنے سے بالآخر یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ
قرآن کریم کا مذکورہ بالا بیان یقیناً یہاں اطلاق پاتا ہے، جیسا کہ ابھی ہم ثابت کریں گے.عیسائیت کی تاریخ سے ہمیں براہ راست ایسی کوئی شہادت نہیں ملتی کہ عیسائی اقوام اپنے باطل
عقائد کی وجہ سے غضب الہی کا مورد ٹھہری ہوں.بلکہ اس کے برعکس وہ تو دنیوی اعتبار سے اللہ تعالیٰ
کے فضلوں کا مورد دکھائی دیتی ہیں.ان اقوام نے ساری دنیا پر حکومت کی ہے اور آج بھی غیر عیسائی
اقوام کے بالمقابل طاقت کا توازن انہی کے حق میں ہے یہاں تک کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ساری دنیا
کی باگ ڈور ان کے ہاتھ میں ہے.اگر چہ گزشتہ چند دہائیوں سے تیسری دنیا کے ممالک بھی کسی قدر
آزادانہ طور پر ترقی کرتے دکھائی دے رہے ہیں.لیکن اسے کوئی بڑی تبدیلی نہیں کہا جاسکتا کیونکہ
آج بھی عیسائی اقوام کی برتری اسی طرح برقرار ہے جسے دیکھ کر انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ اگر
واقعہ ایسا ہی ہے تو پھر قرآن کریم کے مذکورہ بالا بیان کے کیا معنی ہوئے؟
عیسائیت کی تاریخ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آغاز میں عیسائیت اللہ تعالیٰ کی وحدانیت
کے عقیدہ پر ہی قائم تھی.تثلیث اور خدا کے بیٹے کا تصور بہت بعد میں پولوس کے ذریعہ عیسائیت کے
عقائد میں داخل ہوا.اس وقت سے لے کر آج تک اس معمہ کی بہت سی مخصوص تو جیہات پیش کی
جاتی رہی ہیں اور عیسائیت کے مختلف فرقے اس بارہ میں مختلف نظریات اپناتے رہے ہیں.چوتھی
صدی عیسوی کے آغاز سے لے کر اب تک بڑے بڑے عیسائی فرقے اس مسئلہ پر باہم برسر پیکار
دکھائی دیتے ہیں.تثلیث کے متعلق ہر فرقہ درست نظریہ پر قائم رہنے کا دعویدار ہے.اس کے باوجود
سبھی خدائے واحد پر ایمان کا دعوی بھی رکھتے ہیں.بالفاظ دیگر ان کا خدائے واحد اپنی ذات میں گویا
منقسم تھا ان کی اس طرز فکر کی وجہ سے قرآن کریم نے انہیں مشرک نہیں کہا بلکہ انہیں یہ حق دیا ہے کہ وہ
Page 78
66
عدل، احسان اور ایتاء ذي القربى - حصه اول
بے شک تو حید پر ایمان کا دعوی کرتے رہیں تا ہم تو حید کے محض زبانی اقرار کے باوجود ان کے اعمال
مشرکوں والے ہی ہیں.پس سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآنی پیش گوئی پھر کس انداز میں پوری ہوئی؟
زیر نظر آیت پر گہرا غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں جس غضب الہی کا ذکر ہے وہ ایک عظیم
عالمی فساد کی صورت میں ظاہر ہونے والا ہے.اس سے یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ مسیحی عقائد کے اندرہی
دراصل ان کا باہمی انشقاق مضمر ہے.پس جس سزا کا ذکر ہے وہ ان کے جرم کے عین مطابق ہے.تثلیث خدائے واحد و یگانہ کی ذات کو تقسیم کرنے کی ایک کوشش ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس عقیدہ پر
ایمان رکھنے والے خود اندرونی طور پر بٹے ہوئے ہیں.چنانچہ استعماری اقوام کی یہ حکمت عملی کہ
لوگوں
کو تقسیم کر کے ان پر حکومت کرو“ بھی اسی کا ایک شاخسانہ ہے.یورپ میں علم کی نشاۃ ثانیہ عقل اور منطق کے استعمال اور سچائی کی تلاش کا زمانہ ہے.یہی وہ
دور ہے جس میں مغرب کی عیسائی اقوام میں زندگی کی نئی لہر دوڑ گئی اور عیسائی عقائد پر شکوک و شبہات
کا اظہار کیا گیا کہ یہ عقل انسانی سے متصادم ہیں.دانشوروں کی اس بغاوت پر چرچ نے شدید رد عمل
کا اظہار کیا اور عقائد پر اعتراضات کرنے والے لوگوں کی سخت مذمت کی گئی اور انہیں سزائیں دی
گئیں.جب سائنس دانوں اور فلسفیوں کو چرچ کی طرف سے اپنے سوالات کا جواب نہ مل سکا تو وہ
مذہب سے ہی برگشتہ ہو گئے.دراصل چرچ کے چنگل سے نکلتے نکلتے خدا سے بھی دور ہوتے چلے
گئے.یہاں سے سائنسی طرزفکر اور مذہبی عقائد کی راہیں بالکل جدا ہو گئیں.جب تک عیسائی دنیا جہالت کے اندھیروں میں ڈوبی رہی تب تک کوئی مسئلہ کھڑا نہ ہوا تھا.لیکن
جیسے ہی مغرب کے افق پر عقل تحقیق اور علم کا سورج طلوع ہوا تو انہوں نے ہر چیز کو ایک بالکل نئے
تناظر میں دیکھنا شروع کر دیا.انہیں اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ نہ تو زمین ساکن ہے اور نہ ہی یسوع مسیح
کی جائے پیدائش کے احترام میں سورج زمین کا طواف کر رہا ہے.سائنسی انقلابات نے کائنات کا
تصور کلیۂ تبدیل کر کے رکھ دیا.ان پر کھل گیا کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے نہ کہ سورج زمین کے
گرد اور یسوع مسیح کی جائے پیدائش ہونے کی وجہ سے زمین سورج کیلئے قطعاً قابل تعظیم نہیں.جب عیسائی دانشوروں نے حقائق فطرت کو بے نقاب کرنا شروع کیا تو اس خوف سے کہ اسے
کہیں چرچ کی طاقت کے خلاف ایک کھلی کھلی بغاوت ہی نہ سمجھ لیا جائے ، انہوں نے اپنے شبہات کو
مخفی رکھا.چنانچہ لا ادریت پیدا ہوئی جس سے آگے دہریت پر بنی فلسفوں اور اشتراکیت نے جنم لیا.تثلیث کے عقیدے پر باہمی اختلاف سے عیسائی دنیا دو مخالف گروہوں میں یوں
تقسیم ہوئی کہ
ان کے درمیان خلیج بڑھتی ہی چلی گئی اور ایک دوسرے کے خلاف رویے بھی سخت تر ہوتے چلے گئے.
Page 79
عدل سے انحراف
67
دنیا کو دوحصوں میں منقسم قرار دینے پر شاید کسی کو حیرانی ہورہی ہولیکن حقیقت یہ ہے کہ محض مغرب کی
عیسائی دنیا دو گروہوں میں بٹ گئی تھی.لیکن جہاں تک انسانی طاقت کا تعلق ہے تو اس کا مرکز متحدہ
عیسائی طاقتیں اور کمیونسٹ بلاک ہی تھا جو کچھ عرصہ پہلے عیسائیت کا ہی ایک مضبوط گڑھ تھا.اس تناظر میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ گزشتہ دونوں عالمی جنگوں نے انسان کے سیاسی، اقتصادی اور
سماجی رویوں پر نظریات ،عقائد اور فلسفوں کے اثرات کو کافی حد تک واضح کر دیا ہے.عدل کی خلاف ورزیوں
پر متنبہ کرنے والا نظام:
اب ہم ایک ایسے نظام کا مطالعہ کرتے ہیں جو انسانی جسم کے اندر نظامِ عدل کی خلاف ورزیوں
پر متنبہ کرتا ہے.بیماری کے معمولی آثار بھی ظاہر ہوں تو سارا انسانی جسم بے چین ہو جاتا ہے.سطحی
نظر سے دیکھیں تو یہ ایک غیر ضروری مداخلت معلوم ہوتی ہے.لیکن درحقیقت زندگی کی حفاظت اور
بقا کیلئے ایسا ہونا انتہائی ضروری ہے.درد کا احساس ہی ہر نوع حیات میں موجود اس دفاعی نظام کو
بیدار کرتا ہے جو عام حالات میں فعال نہیں ہوتا.درد اور بے چینی نہ صرف عمومی طور پر سارے جسم کو
بیماری سے آگاہ کرتے ہیں بلکہ یہ دفاعی نظام کی معین رہنمائی کرتے ہیں کہ جسم میں خطرہ کہاں ہے؟
خطرے اور اس کے مقام کی تعیین کے بعد دفاعی نظام خطرے کی جگہ اور نوعیت کے مطابق اس سے
نبرد آزما ہونے کیلئے مناسب اقدامات کرتا ہے.زندگی کا دفاعی نظام صرف درد کی وجہ سے بیدار نہیں
ہوتا بلکہ ہر قسم کے خطرے کا مقابلہ کرنے کیلئے ، جوکسی بھی فرد کی زندگی کو در پیش ہے، بیدار ہو جاتا ہے
اور پھر ہر نوع حیات میں یہ نظام ایک ردعمل دکھاتا ہے جو کہ بہت بار یک تفاصیل پر مبنی ہوتا ہے.اس
سے دفاعی وسائل جسم میں نہ صرف پیدا ہوتے ہیں بلکہ انہیں معین مقام تک پہنچایا جاتا ہے جہاں ان
کی ضرورت ہوتی ہے.انسان کو دیگر جانوروں سے ممتاز کرنے والا ایک ایسا خاص نظام عطا کیا گیا ہے جو نہ صرف جسم پر
بیماری کے حملے سے متنبہ کرتا ہے بلکہ انسان کے اخلاقی شعور کو اپنی ذات سے متعلق اور خدا تعالیٰ سے متعلق
بھی بیدار کرتا ہے اور انسان اور خدا تعالیٰ کے مابین تعلق کے حوالے سے بہت اہم کردار ادا کرتا ہے.اسی قسم کا ایک تنبیہ اور دفاع کا نظام انسان کے مذہبی اور اخلاقی اعمال کے تعلق میں کارفرما
ہے.قرآن کریم مذہب کی تاریخ کو انبیا کے ساتھ ان کے مخالفین کے سلوک کے حوالے سے پیش
کرتا ہے اور مختلف ادوار میں انسان کے اخلاقی اور معاشرتی زوال
کا مفصل تجزیہ کرتا ہے.جب کسی
قوم کو آنے والی تباہی سے بچانے کیلئے اس میں انبیا کو مبعوث کیا گیا تو اکثر و بیشتر ان کی شدید
Page 80
68
عدل، احسان اور ایتاء ذي القربى - حصه اول
مخالفت کی گئی لیکن خود مخالفین کو ہی اس اندھی مخالفت کے نتائج بھگتنا پڑے.یعنی یا تو انہیں صفحہ ہستی
سے مٹادیا گیا یا پھر وہ رفتہ رفتہ ایسے زوال پذیر ہوئے کہ ذکر کے قابل بھی نہ رہے.قرآن کریم ایسے بہت سے لوگوں کے حالات بیان کرتا ہے جنہوں نے عدل وانصاف کے
تقاضوں کو نظر انداز کر دیا.اس میں آئندہ نسلوں کیلئے عبرت کا سامان ہے.متنبہ کرنے والا یہ نظام انسان کے ایمان اور عقائد کے تمام پہلوؤں پر محیط اور حاوی ہے.توحید باری تعالیٰ کیلئے کلیۂ وقف ہو جانے کو ایمان کا بلند ترین مقام کہا جاسکتا ہے جبکہ ایمان کے نچلے
درجے پر انسان کا روزمرہ کا طرز عمل ہے جو ایک سچے مومن کو کافر سے ممتاز کرتا ہے.روزمرہ کے
اس طرز عمل کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مومن کو نصیحت فرماتے ہیں کہ وہ دوسرے لوگوں کو
در پیش ہر قسم کے امکانی خطرات کو دور کرنے کی عادت ڈالے.اس امر کی وضاحت کرتے ہوئے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رستے میں پڑی ہوئی کئی ایسی چیزوں
کا ذکر فرمایا ہے جو راہ چلتے ہوؤں کیلئے
باعث تکلیف ہو سکتی ہیں.نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انتباہ بھی فرمایا ہے کہ اگر کوئی مومن رستہ
میں پڑا ہوا ناخن کا نشایا ایسی چیز جو ایک بے خبر آدمی کیلئے تکلیف کا باعث ہو سکتی ہے ،نہیں ہٹاتا تو اس
کا ایمان اسی حد تک کمزور ہو گا.اللہ تعالیٰ کی طرف لے جانے والا رستہ بھی خطرات سے پر ہے جو
آغاز میں چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں لیکن رفتہ رفتہ بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں.اسلامی تعلیم کا یہ وہ دلچسپ حصہ ہے جس کا مطالعہ اسلام کے متعلق بحیثیت مجموعی ہمارے علم کو
وسعت اور گہرائی عطا کرنے میں مدد دیتا ہے.ایک اور موقع پر اسی بارے میں گفتگو کرتے ہوئے
حضرت اقدس محمد مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح انسان دیگر اشیا پر اپنا حق رکھتا ہے.اسی
طرح تمام اشیا کے بھی انسان پر حقوق ہیں.بازاروں ،سڑکوں اور رستوں کے حقوق ہیں جو ان کو استعمال
کرنے والوں پر عائد ہوتے ہیں.بازاروں کے حقوق کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں
توجہ دلائی ہے کہ عوامی جگہوں یا سڑکوں پر بلا مقصد کھڑا رہنا اور آمد ورفت میں رکاوٹ کا باعث بننا
ناپسندیدہ فعل ہے.اسی طرح دکانوں وغیرہ کو وسعت دینے کیلئے ناجائز تجاوزات قائم کر لینا بھی آپ
صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے منافی ہے.آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے ستر درجات ہیں
جن میں سے سب سے چھوٹا درجہ رستوں میں حائل تمام رکاوٹوں کو دور کرنے کی عادت ہے.سوال یہ ہے کہ یہ کس طرح ایمان کا جزو ہو گیا ؟ ذرا سا غور کرنے سے اس میں مضمر حکمت بآسانی
سمجھ میں آسکتی ہے وہ یہ کہ حقیقی ایمان باللہ اس امر کا متقاضی ہے کہ جو حفاظت اور امن خدا تعالیٰ کی
Page 81
عدل سے انحراف
69
طرف سے انسان کو میسر ہے اسے دوسری مخلوق تک بھی پہنچایا جائے.پس اگر کوئی دوسروں کی
حفاظت اور امن کی ذمہ داری سے غافل ہے تو اس کا ایمان کمزور ہے.اس سے صاف ظاہر ہے کہ اسلامی تعلیمات کا دائرہ انسان کی ادنی ترین ضروریات پر بھی
حاوی ہے.لیکن یہ امر مضحکہ خیز ہونے کے ساتھ ساتھ دردناک بھی ہے کہ آج اکثر مسلم ممالک میں
ان بنیادی تعلیمات کی خلاف ورزی عام ہے.سڑکوں اور رستوں کی مرمت ہی نہیں ہوتی اور ان کی
حالت ناگفتہ بہ ہے یہاں تک کہ بعض حکومتی ادارے بھی جب پائپ یا تاریں وغیرہ بچھانے کیلئے
اہم اور بڑی بڑی شاہراہوں پر کھدائی کرتے ہیں تو انہیں ویسا ہی کھلے کا کھلا چھوڑ دیتے ہیں.وہاں
نہ تو خطرہ کی نشان دہی کرنے کیلئے کوئی روک کھڑی کی جاتی ہے اور نہ ہی رات کو سفر کرنے والوں
کیلئے روشنی کا انتظام کیا جاتا ہے حالانکہ گزرنے والوں
کیلئے وہ جگہ ہلاکت خیز ہوتی ہے.بد قسمتی سے سڑکوں پر ہونے والے بہت سے حادثات تنبیہ کے اس نظام کو نظر انداز کر دینے کے
نتیجے میں وقوع پذیر ہورہے ہیں.مثلاً ایک مرتبہ میں اسلام آباد میں اپنی کار پر کہیں جارہا تھا.میں نے
کار کی ہیڈ لائٹس نیچی کی ہوئی تھیں کہ مجھے شک گزرا کہ سڑک کے درمیان کوئی غیر معمولی چیز پڑی ہوئی
ہے.خطرے کو بھانپتے ہی میں نے فوراً بریک لگائی تو معلوم ہوا کہ چند گز آگے سڑک کے آر پار ایک
بہت بڑا گڑھا کھدا ہوا ہے اور اس کے باوجود وہاں نہ تو کوئی سرخ نشان تھا اور نہ ہی روشنی کا خاطر خواہ
انتظام تھا.اس پر مستزاد یہ کہ گڑھے کے ارد گرد سے مٹی بھی ہٹا دی گئی تھی حالانکہ اگر وہ ہوتی تو کم از کم
و ہی مسافروں کو خطرے سے آگاہ کرنے کا ایک ذریعہ بن جاتی.چنانچہ ہم محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے
ہی محفوظ رہے.میں اپنے اہل وعیال کے ساتھ سفر کر رہا تھا اگر میں اچانک بریک نہ لگا تا تو یقینا ہم
سب ایک مہلک حادثے سے دو چار ہو جاتے.جیسا کہ اگلے ہی دن یہ خبر ملی کہ کسی جرمن سیاح کی نئی
مرسڈیز کا راسی گڑھے کی نذر ہوگئی.خدا کرے کہ اس کی جان بچ گئی ہو.آمین
اسی قسم کا ایک اور واقعہ ہمیں شیخو پورہ سے گوجرانوالہ جانے والی سڑک پر بھی پیش آیا.فرق
صرف یہ ہے کہ وہاں کھری ہوئی سڑک کا ملبہ بھی موجود تھا اس لئے رات کو موٹر چلاتے ہوئے جب
اچانک مٹی کے ڈھیر پر میری نظر پڑی تو میں اس سے ٹکرانے سے پہلے ہی بریک لگانے میں کامیاب
ہو گیا.وہاں بھی گاڑی چلانے والوں کیلئے خطرے سے آگاہی کا کوئی نشان موجود نہ تھا.گڑھا اتنا بڑا
تھا کہ جب ہم نے کار سے اتر کر اس کے اندر جھانکا تو یہ دیکھ کر دہشت زدہ ہو گئے کہ ایک سالم بس
اس گڑھے میں گری پڑی تھی جس کا اب محض ڈھانچہ ہی باقی رہ گیا تھا.
Page 82
70
عدل، احسان اور ایتاء ذي القربى - حصه اول
یہ صرف دو مثالیں ہیں جو میں نے پیش کی ہیں ورنہ روزانہ ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں.اس
سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ جہاں نظام عدل کی یہ حالت ہو کہ انسانی حقوق کے ادنی تقاضے بھی
پورے نہ ہورہے ہوں وہاں اس کے نتائج انتہائی ہولناک ہو سکتے ہیں.اس قسم کے معاشرے میں ہم
دیگر بنیادی حقوق کی حالت کا بھی بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں.پس اس پیغام کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک مسلم
معاشرے کو ادنی ترین درجہ پر بھی عدل کے احکام کو پس پشت نہیں ڈالنا چاہئے.
Page 83
مذہب کی تشکیل میں تین تخلیقی اصولوں کا کردار
-8
مذہب کی تشکیل میں تین تخلیقی اصولوں کا کردار
71
قوانین عدل انسان کے اس طرز عمل پر بھی اطلاق پاتے ہیں جو مذہب کے دائرے میں آتا
ہے.مذہب کے حوالے سے ہم اپنی گفتگو کا آغاز اس دور سے کرتے ہیں جو قر آنی تعلیم سے پہلے کا
زمانہ ہے یعنی وہ دور جس میں سب سے پہلے حضرت آدمؑ پر بنی نوع انسان کی ہدایت کیلئے مذہبی
تعلیم نازل فرمائی گئی.اس ابتدائی تعلیم کے جو خد و خال قرآن کریم نے محفوظ فرمائے ہیں ان سے
یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ وہ بنیادی طور پر سماجی اور معاشی انصاف سے متعلق تھے.حضرت آدم کا دین ایسی مضبوط بنیادیں استوار کرتا دکھائی دیتا ہے جن پر بتدریج آسمانی
تعلیمات کی عمارت تعمیر ہوئی ہے.وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا
گیا اور محض عدل سے جو گفتگو شروع ہوئی تھی وہ احسان اور ایتا عذی القربی جیسی اعلیٰ تعلیمات تک
جا پہنچی.مختصر یہ کہ حضرت آدم کے زمانے سے لے کر حضرت اقدس محمد مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم کے
زمانے تک ایک معین ارتقائی عمل کے مختلف مراحل کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے جہاں مذہب اپنے
نقطہ کمال کو پہنچتا ہوا دکھائی دیتا ہے جبکہ دیگر مزعومہ مذاہب یا تو دیو مالائی قصے کہانیاں ہیں یا پھر آسمانی
مذاہب کی بگڑی ہوئی ایسی شکلیں جو انسانی دست برد کا شکار ہو چکی ہیں.حضرت آدم علیہ السلام کا دور:
نبوت آسمان سے روشنی کا ایسا پیغام لاتی ہے جس کے سامنے اس زمانے کے لوگوں کو یا تو
سرتسلیم خم کرنا پڑتا ہے یا پھر اپنی خطاؤں اور گناہوں کے طبعی نتائج بھگتنا پڑتے ہیں.سوال یہ ہے کہ یہ
کس قسم کا عدل ہے جو انبیاء کے اس حاکمانہ کردار کی طرف منسوب کیا جاسکتا ہے.الہامی مذہب کی
آمد سے پہلے معاشرہ اپنے قائدین کو منتخب کرنے اور پھر ان کی اطاعت کرنے یا نہ کرنے میں کلیۂ
آزاد تھا.تو پھر اچانک انسان کو ایک دوسرے انسان کی اطاعت پر کیوں مجبور کر دیا گیا ؟ قرآن کریم
اس اشکال کا حل یوں پیش کرتا ہے کہ حضرت آدم کو دوسروں پر کوئی ذاتی فضیلت حاصل نہ تھی.وہ
بھی دیگر انسانوں جیسے ایک انسان ہی تھے اور انہیں دیگر لوگوں کو اپنی اطاعت پر مجبور کرنے کا کوئی حق
حاصل نہ تھا.لیکن جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر نفخ روح کیا یعنی اپنا کلام اور حکم ڈالا تب انہیں یہ
حق مل گیا.نفخ روح کی قرآنی اصطلاح کا مطلب انسان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کا نزول
ہے.چنانچہ فرمایا:
Page 84
72
عدل، احسان اور ایتاء ذي القربى - حصه اول
وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكَةِ إِنِّى خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ
حَمَامَّسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ
سجِدِينَ
(30,29:15 31)
ترجمہ: اور (یاد کر) جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں گلے سڑے
کیچڑ سے بنی ہوئی خشک کھنکتی ہوئی ٹھیکریوں سے بشر پیدا کرنے والا ہوں.پس جب میں اسے ٹھیک ٹھاک کرلوں اور اس میں اپنا کلام پھونکوں تو اس کی
اطاعت میں سجدہ ریز ہو جانا.ایسا ہی ذکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سورۃ کہف میں یوں ملتا ہے:
قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَى أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ
فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ
بِعِبَادَةِ رَبَّةٍ أَحَدًا
(الكهف 111:18)
ترجمہ: کہہ دے کہ میں تو محض تمہاری طرح ایک بشر ہوں.میری طرف وحی کی
جاتی ہے کہ تمہارا معبود بس ایک ہی معبود ہے.پس جو کوئی اپنے رب کی لقاء
چاہتا ہے وہ ( بھی ) نیک عمل بجالائے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو
شریک نہ ٹھہرائے.نفخ روح کی اولین شرط ” تقوی، یعنی خوف خدا ہے.مراد یہ ہے کہ حقیقی معنوں میں خوف خدا
رکھنے والا ہی مکالمہ ومخاطبہ الہیہ سے مشرف کیا جاتا ہے.چنانچہ صرف اور صرف تقویٰ ہی باعث
عزت و تکریم ہے.نفخ روح (سورۃ الحجر: 30) یعنی اللہ تعالیٰ کا کسی کے اندر ” زندگی کی روح پھونکنا“ کے الفاظ
ہمیشہ صرف انسانوں کیلئے استعمال ہوئے ہیں، جانوروں کے تعلق میں یہ الفاظ استعمال نہیں ہوئے.نفخ “ سے مراد کسی چیز میں پھونکنا ہے.اس اصطلاح کے اول معنی زندگی کی روح پھونکنا ہے لیکن
اس سیاق وسباق میں یہ اصطلاح صرف انسانوں کیلئے ہی مخصوص ہے.تمام جانداروں میں انا اور
شعور کا ایک مرکز ہوتا ہے لیکن یہ شعور اپنی ذات میں اس قابل نہیں ہوتا کہ جسمانی زندگی کے بعد بھی
زندہ رہ سکے.روح کے بالمقابل ”زندگی“ کی اصطلاح استعمال ہوئی ہے جو کہ تمام جانداروں کو
دی گئی ہے لیکن روح صرف انسانوں کو عطا کی گئی ہے.
Page 85
مذهب کی تشکیل میں تین تخلیقی اصولوں کا کردار
73
قرآن کریم کی ایک اصطلاح «نفس“ ہے جو بکثرت استعمال ہوئی ہے جس کا سیدھا سادا
مطلب ہے ”زندگی“.لیکن یہ روح کی طرح معین اصطلاح نہیں ہے.ہر جاندار نفس یعنی زندگی
رکھتا ہے لیکن ہر زندہ چیز روح نہیں رکھتی.ان دونوں اصطلاحات میں یہی بنیادی فرق ہے.روح،
شعور کی دوسری اور زیادہ ترقی یافتہ حالت کا نام ہے جو جسم کے مرنے پر اس سے جدا ہو جانے کے
باوجود از خود زندہ رہنے کی اہلیت رکھتی ہے.توانائی کی اس اکائی کی وضاحت ممکن نہیں کیونکہ انسانی علم
ابھی اس مقام تک نہیں پہنچا جہاں وہ روح کی ماہیت کو سمجھ سکے.بہر حال
انسانی فہم و ادراک کی سہولت
کی خاطر قرآن کریم روح کو كَلِمَةُ الله “ قرار دیتا ہے.اس سے زیادہ انسان روح کو نہیں سمجھ سکتا.نفع کا بنیادی معنی وحی الہی ہے چنانچہ وحی کے سارے عمل کا احاطہ یہی اصطلاح کرتی ہے.روح کی پیدائش زندگی کے ارتقا کا اگلا قدم ہے.روح کہیں باہر سے نہیں آیا کرتی بلکہ یہ پہلا بلند
مرتبہ ہے جو خدا تعالیٰ انسانوں کو عطا کیا کرتا ہے جبکہ وحی الہی دوسرا بلند تر درجہ ہے جس کے ذریعے
خدا تعالیٰ اپنے چنیدہ بندوں کو عام لوگوں سے ممتاز کر کے دکھلاتا ہے.وحی الہی سے مشرف ہونے
والوں میں سے بعض نبوت جیسے بلند تر مقام پر سرفراز کئے جاتے ہیں.پس نخ روح کے ذریعے
زمین پر خدا تعالیٰ کے خلیفہ کی پیدائش اس اصطلاح کے اعلیٰ اور لطیف معنی ہیں.اس نقطہ نگاہ سے نبی
اللہ کی اطاعت کو نہ تو خلاف عدل کہا جا سکتا ہے اور نہ ہی خلاف عقل قرار دیا جا سکتا ہے کیونکہ نبی
صرف اور صرف خلیفہ اللہ کی حیثیت سے ہی اطاعت کا مستحق ٹھہرتا ہے.خدا تعالی کی نمائندگی کا استحقاق اسی کو ہوتا ہے جو سچائی کے ساتھ کامل وابستگی کی بدولت ہمیشہ
خدا تعالیٰ کا معتمد ہوتا ہے.چنانچہ ناممکن ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیغام کے تعلق میں بنی نوع
انسان کے ساتھ کسی بھی قسم کی نا انصافی کا مرتکب ہو.اللہ تعالیٰ اس کی تمام صلاحیتوں کو ایک کامل
تناسب اور توازن کے کمال تک پہنچانے کے بعد ہی اسے نبوت کے اعلیٰ مقام پر سرفراز کیا کرتا ہے
اور اپنا کامل اعتماد اسے عطا فرماتا ہے اور وہ بندہ کبھی بھی اس اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچاتا.ان خلفاء
میں بعض تو صاحب شریعت نبی ہیں جو شریعت خداوندی کے نئے دور کا آغاز کرتے ہیں.جب تک یہ دور
جاری رہتا ہے ان کے نقش قدم پر آنے والے انبیاء کوئی نئی شریعت نہیں لاتے.وہ حاملین وحی نبوت
ہوتے ہیں اور خدا تعالی کی نمائندگی میں دیگر فرائض بھی سرانجام دیتے ہیں.مثلاً خدا تعالیٰ کی ہستی پر
لوگوں کے ایمان کو مضبوط کرنا اور معاشرے کی اصلاح کرنا.قرآن کریم کے نزدیک خدا تعالیٰ کی عبادت، مقررہ طریق پر نماز کی ادائیگی اور نیک کاموں
Page 86
74
عدل، احسان اور ایتاء ذي القربى - حصه اول
کیلئے مال کا خرچ کرنا.وہ تین بنیادی تعلیمات ہیں جو تمام مذاہب میں پائی جاتی ہیں.چنانچہ
قرآن کریم فرماتا ہے:
وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا
الصَّلوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكُوةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ (البينة 6:98)
ترجمہ: اور وہ کوئی حکم نہیں دیئے گئے سوائے اس کے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں،
دین کو اس کے لئے خالص کرتے ہوئے ، ہمیشہ اس کی طرف جھکتے ہوئے اور
نماز کو قائم کریں اور زکوۃ دیں.اور یہی قائم رہنے والی اور قائم رکھنے والی
تعلیمات کا دین ہے.حضرت آدم علیہ السلام کی جنت :
حضرت آدم کو عطا کی جانے والی شریعت اس عالمگیر اصول سے مختلف نہیں ہو سکتی تھی.مندرجہ بالا آیات میں خدا اور انسان کے باہمی تعلق کی وضاحت کی گئی ہے اور انسان کے انسان کے
ساتھ تعلق کے اصول یعنی وہ شریعت جو حضرت آدم علیہ السلام کو عطا کی گئی قرآن کریم نے دو آیات
میں کر دی ہے.ان میں سے پہلی آیت جس کثرت سے بیان کی جاتی ہے اسی قدر اس سے غلط مطلب
اخذ کیا جاتا ہے.یہ بہشت کے دو درختوں سے متعلق حضرت آدم علیہ السلام کو دیئے گئے حکم خداوندی
کے بارے میں ہے ان میں سے ایک درخت کے متعلق تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حوا کو
اجازت دے رکھی تھی کہ بلا روک ٹوک جہاں سے چاہیں اس کا پھل کھائیں لیکن دوسرے درخت
سے دور رہنے کی آدم کو تاکیدی نصیحت فرمائی تھی.قرآن کریم میں یہ درخت، شجرہ خبیثہ کے طور پر
مذکور ہے.عام طور پر لوگ اس کے ظاہری معنی لیتے ہیں اور اسے زمین پر پائے جانے والے پھل دار
درختوں جیسا ہی ایک درخت سمجھتے ہیں اور چونکہ یہ بیان عہد نامہ قدیم کے بیان سے بہت مشابہ ہے
اس لئے مسلم، یہود اور عیسائی مفسرین نے استعارہ استعمال ہونے والے ان الفاظ میں مضمر معانی کو
سمجھنے کی کوشش کی ہے.میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ مختلف علماء نے اس سے کیا کیا استنباط کیا ہے لیکن میں
پورے وثوق سے کہ سکتا ہوں کہ ان دونوں درختوں سے مراد شریعت خداوندی کے اوامر و نواہی پر
مشتمل تعلیم ہی ہے جو حضرت آدم کو دی گئی تھی.شجرہ خبیثہ کا تعلق شریعت کے اس حصے سے ہے جس
Page 87
مذهب کی تشکیل میں تین تخلیقی اصولوں کا کردار
75
میں اللہ تعالیٰ نے مذہبی معاشرے کو باہمی تعلقات میں اخلاق اور عدل کے احکام کی حدود سے تجاوز
کرنے سے منع فرمایا ہے.تاہم اس کے معانی کی تعیین کو انسان کی سمجھ پر ہی نہیں چھوڑ دیا گیا جس
کے عدل اور دیانت وغیرہ کے تصورات دیگر انسانوں سے مختلف ہو سکتے ہیں.اس کی روک تھام کیلئے
انبیاء علیہم السلام کو دی گئی تعلیم نہایت واضح اور جامع ہے.دوسرا درخت وہ ہے جس پر طیب پھل لگتے ہیں.اس میں سے جہاں سے چاہیں کھانے پر آدم
علیہ السلام اور حوا کو آزادی دی گئی.اس سے واضح طور پر آدم علیہ السلام کو دی گئی شریعت کے مثبت
احکام یعنی اوامر مراد ہیں.اگر چہ اس آیت میں مجوزہ ضابطہ اخلاق کے بنیادی خاکے کی تفصیلات بیان نہیں کی گئیں پھر
بھی اس سے بآسانی یہ استنباط کیا جاسکتا ہے کہ آدم اور ان کی جماعت کو ایک دوسرے کے بنیادی
حقوق پامال کرنے سے منع کر دیا گیا کیونکہ یہی باتیں ہیں جو ہمیشہ نقض امن اور سخت تکلیف کا باعث
ہوا کرتی ہیں.اسی موضوع پر ایک اور آیت اس ابتدائی معاشرے کے مناسب حال، اقتصادی عدل کے
ضابطے کی بنیادیں استوار کرتی دکھائی دیتی ہے.إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوْعَ فِيْهَا وَلَا تَعْرَى وَاَنَّكَ لَا تَطْمَؤُا فِيهَا
وَلَا تَضْحى
(120,119:20; b)
ترجمہ: تیرے لئے مقدر ہے کہ نہ تو اس میں بھوکا رہے اور نہ ننگا اور یہ (بھی)
کہ نہ تو اس میں پیاسا ر ہے اور نہ دھوپ میں جلے.پس اقتصادی پہلو سے حضرت آدم کی تعلیمات میں ایک معاشرے کی تشکیل کے آغاز میں ہی
چار بنیادی حقوق انسان کو دیئے گئے ہیں:
(۳
ہر انسان کا حق ہے کہ اسے مناسب غذا ملے.کوئی بھی بھوکا نہیں رہے گا،
مناسب لباس بھی ہر شخص کا بنیادی حق ہے،
ہر شخص کو صاف اور صحت بخش پانی کی فراہمی کی ضمانت دی گئی ہے،
(۴) کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہو گا جسے سر چھپانے کی جگہ میسر نہ ہو.تاہم کثر علماء کے نزدیک حضرت آدم علیہ السلام کے قصے میں جس جنت کا ذکر ہے وہ دراصل
وہی جنت ہے جس کا آخرت میں مومنین سے وعدہ کیا گیا ہے.ایسے نظریات پر غور کریں تو انسان یہ
Page 88
76
عدل، احسان اور ایتاء ذي القربى - حصه اول
دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کہ عالم آخرت کا جو نقشہ کھینچا گیا ہے وہ اس جنت سے یکسر مختلف ہے جو
حضرت آدم علیہ السلام اور آپ کے پیروکاروں کو عطا کی گئی تھی.یہ کیسی جنت ہے جس میں کھانے کو
صرف اتناہی میسر ہے جس سے بمشکل بھوک مٹائی جا سکے اور جہاں پینے کو سادہ پانی بتن ڈھانکنے کو
چند کپڑے اور سر چھپانے کیلئے چھت میسر ہے.قرآن کریم نے نیک لوگوں کو مرنے کے بعد کسی ایسی
جنت کے ملنے کا کوئی ذکر نہیں کیا اور نہ ہی کسی کو کوئی ضرورت پڑی ہے کہ اس جنت کی خاطر دنیا کی
خوشیوں اور نعماء سے دست کش ہو جائے.ترقی یافتہ معاشروں کے پسماندہ ترین لوگ بھی اس سے کہیں بہتر جنت سے لطف اندوز ہو
رہے ہیں جس قسم کی جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کو نکالا گیا تھا.ہمیں یہ یقین کرنے میں بڑا تامل
ہے کہ کٹر ملاؤں کو ایسی جنت کی خواہش ہوگی جہاں ایک بے کس لا چار عورت ہو اور ایک تنہا شجر ممنوعہ
اور اسی قبیل کے کچھ اور پھلدار پودے بھی موجود ہوں لیکن ساتھ ہی کافی تعداد میں سانپ بھی موجود
ہوں.مناسب لباس کا وعدہ بھی ایفا ہوتا نظر نہ آئے جب آدم علیہ السلام اور حوا آنکھ کھلنے پر خود کو
برہنہ دیکھیں.نہ تن ڈھانکنے کو کپڑے ہوں ، نہ سر چھپانے کیلئے چھت ستر پوشی کیلئے محض جنت کے
نہ
درخت کے کچھ پتے ہوں! کیا کوئی نیک انسان ایسی شاندار جنت میں داخل ہونے کی تمنا کر سکتا
ہے؟ افسوس! کہ وہ سمجھتے نہیں.یقیناً یہ وہ جنت تو نہیں جس کا قرآن کریم نے مومنوں سے نیک
اعمال اور قربانیوں کے بدلے آخرت میں بطور انعام دینے کا وعدہ فرمایا ہے.یہ تو اُس اقتصادی تصور پر بھی کوئی فوقیت نہیں رکھتی جسے کارل مارکس نے سائنسی سوشلزم کے
فلسفے کی بنیاد پر پیش کیا ہے.قرآن کریم کے نزدیک یہ وہ پہلا وعدہ ہے جو آدم اور حوا کی کہانی میں
انسان کو دیا گیا ہے.اسے بنیادی انسانی حقوق کا اولین منشور بھی قرار دیا جاسکتا ہے.بلکہ یہ تو سائنسی
سوشلزم کی جنت ارضی کے تصور سے بھی بڑھ کر ہے.اشترا کی فلسفے کا بغور مطالعہ ہمارے اس نقطہ نظر
کی بھر پور تائید کرتا ہے کہ مارکسزم اور لینن ازم محض تین بنیادی حقوق تک ہی محدود ہیں اس سے زیادہ
ان میں کچھ بھی نہیں، باقی سب کچھ اختیاری ہے جو مہیا کیا بھی جاسکتا ہے اور نہیں بھی.سائنسی
سوشلزم محض غذا، چھت اور لباس کے حقوق کی ضمانت دیتا ہے.قرآن کریم کا پیش کردہ اقتصادی عدل کا بنیادی تصور اشترا کی آئیڈیل سے وسیع تر ہے.اشتراکی معاشروں میں غالباً اس غلط خیال کی وجہ سے پانی کی ضمانت نہیں دی گئی کہ یہ کوئی زیادہ اہم
بات نہیں ہے.ماہرین کے پیش کردہ حقائق اور اعداد و شمار ایک بالکل مختلف کہانی بتاتے ہیں جن کے
Page 89
مذهب کی تشکیل میں تین تخلیقی اصولوں کا کردار
77
مطابق افریقہ اور ایشیا میں لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد پانی کی نہایت قلیل مقدار پر بمشکل گزارہ کر
رہی ہے اور جو پانی میسر ہے وہ بالعموم صحت کیلئے سخت مضر اور نا قابل استعمال ہے.حال ہی میں
اقوام متحدہ کی متعلقہ تنظیمیں پانی کی اہمیت اور صحت بخش پانی کی مناسب مقدار میں فراہمی کے حقوق
پر سنجیدگی سے غور کر رہی ہیں.پس جنت کے بارے میں قرآنی تصور کی فضیلت کا اندازہ لگائیں
جہاں
بالکل ابتدائی اور بنیادی سطح پر پانی کی اہمیت کو سمجھا گیا ہے اور اسے معمولی خیال نہیں کیا گیا.نبوت کا اپنے کمال کی طرف سفر :
حضرت آدم کے بعد انبیا کا سلسلہ جاری رہا اور یہ مرقرین قیاس ہے کہ حضرت آدم کے بعد اور
حضرت نوح سے پہلے کئی انبیاء گزرے ہوں تاہم قرآن کریم میں ان
کا ذکر نہیں ملتا جس کی وجہ یہ ہو
سکتی ہے کہ وہ صاحب شریعت نبی نہیں تھے.حضرت نوح کے زمانے تک وہ شریعت نافذ رہی جو
حضرت آدم کو عطا ہوئی تھی.حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک انسانی تہذیب و تمدن نے کافی ترقی کی.اگر حضرت
نوح دجلہ اور فرات کی سرزمین میں مبعوث کئے گئے تھے تو تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ یہ علاقہ ایک
اچھا خاصا ترقی یافتہ تجارتی مرکز بن گیا تھا جہاں دور دراز سے تجارتی قافلے کھنچے چلے آتے
تھے.سازگار موسمی حالات کے باعث میسو پاناما (Masopatama) کے علاقے میں بسنے والی
خانہ بدوش اقوام جن کا گزارہ محض شکار پر تھا ، نے زراعت پر مبنی ثقافت کی بنیاد رکھی اور مستقل
آبادیاں بنا کر رہنے لگیں.آب پاشی کے طریق، دھات کاری، ظروف سازی، فن تعمیر اور دیگر
کاموں میں انہوں نے کافی ترقی کی.قرآن کریم کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ
پسپائی (POMPET) کے اس معاشرہ کی مانند ایک آسودہ حال معاشرہ تھا جو شدید زلزلے اور
آتش فشاں کے پھٹنے کے باعث صفحہ ہستی سے مٹ گیا تھا.اس ترقی یافتہ انسانی معاشرہ کو بدلتے ہوئے حالات اور بڑھتے ہوئے معاشرتی تقاضوں کے
پیش نظر زیادہ ترقی یافتہ آسمانی تعلیم کی ضرورت تھی.قرآن کریم کے مطابق حضرت نوح کے زمانہ
کے لوگ ہر قسم کے ظلم میں ملوث تھے نیز پورا معاشرہ صراط مستقیم سے ہٹ کر گناہوں کی دلدل میں
ھنس چکا تھا.اس سے بآسانی یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ ان پر گناہ کے تصور کو خوب اچھی طرح واضح کر
دیا گیا تھا کیونکہ شریعت کے بغیر گناہ کے کوئی معنی نہیں ہیں.چنانچہ مذہبی اصطلاح میں گناہ سے مراد
شریعت کی خلاف ورزی ہے.دنیا کے مختلف خطوں اور مختلف ادوار میں مبعوث ہونے والے انبیاء کی امتوں کا بھی یہی حال
Page 90
78
عدل، احسان اور ایتاء ذي القربى - حصه اول
ہے تاہم قرآن کریم نے غیر ضروری تفاصیل کو چھوڑتے ہوئے ان کی تعلیمات کا صرف عمومی رنگ میں
ذکر فرمایا ہے.حضرت اسحاق علیہ السلام ، حضرت اسماعیل علیہ السلام ، حضرت یعقوب علیہ السلام
اور حضرت یوسف علیہ السلام اس شریعت کے تابع تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کی گئی تھی.چنانچہ ان کے مذہب کا مرکزی نقطہ مکمل وفاداری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور سنت ابرا ہیمی علیہ
السلام کی پیروی نیز ان کی لائی ہوئی تعلیمات پر عمل قرار پایا.”ملت“ کے لفظ میں یہ مفہوم پوری
طرح شامل ہے تاہم ان تعلیمات کی تفصیل یہاں بیان نہیں ہوئی.لیکن قرآن کریم سے قبل ظاہر
ہونے والی تمام شرائع پر ہمیشہ یہ رہنما اصول اطلاق پاتا ہے کہ خدا تعالیٰ لوگوں پر ہمیشہ ان کی
استطاعت کے مطابق ہی بوجھ ڈالا کرتا ہے.یعنی وہ ہمیشہ لوگوں کی ضروریات اور ان کے اقتصادی،
معاشرتی اور اخلاقی ماحول کے مناسب حال اعمال کا ہی مکلف ٹھہرایا کرتا ہے.حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ تک یہی سلسلہ جاری رہا لیکن موسوی شریعت پہلے انبیاء کی
شریعت کی نسبت زیادہ تفصیل سے بیان کی گئی ہے.اس شریعت کے بعض احکام کی وضاحت کرتے
ہوئے قرآن کریم حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانہ میں غذا سے متعلق ہدایات پر بھی روشنی ڈالتا ہے.قرآن کریم میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو متعدد پہلوؤں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مثیل قرار دیا
گیا ہے.اسی طرح عہد نامہ قدیم (استثناء 18:18) میں مذکور مماثلت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو
مستقبل میں مبعوث ہونے والے ایک نبی کی خبر دی گئی جس کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ اس کے
بھائیوں میں سے اور اس کی مانند ہوگا.قرآن کریم میں موسوی شریعت کا اتنا تفصیلی ذکر کیوں ہے جبکہ حضرت نوح علیہ السلام جیسے
عظیم الشان صاحب شریعت نبی کی تعلیمات کے متعلق وہ بالکل خاموش ہے؟ اس سوال کے جواب
میں یادرکھنا چاہئے کہ قرآن کریم کے مطابق محمدی شریعت کا براہ راست موسوی شریعت سے موازنہ
کیا جاسکتا ہے.دونوں
انبیاء میں مماثلت پائی جاتی ہے.لیکن چونکہ قرآنی شریعت اکمل ترین ہونے
کی دعویدار ہے لہذا جہاں کہیں بھی ان دونوں میں اختلاف دکھائی دیتا ہے، وہیں اس دعوے کی
تصدیق ہو جاتی ہے.چنانچہ دیگر وجوہات کے علاوہ موسوی شریعت کی اہم تعلیمات کو محفوظ رکھنے کی
ایک وجہ یہ باہمی موازنہ بھی ہے.چنانچہ مذہب کے ارتقا میں یہ بہت ہی اہم سنگ میل ہے جس کی
تشکیل خاص منشائے الہی کے تحت ہوئی ہے.موسوی شریعت میں عدل پر بہت زور دیا گیا ہے.عفو کا
ذکر بھی ملتا تو ہے لیکن استثنائی اور محض ایک متبادل کے طور پر جبکہ عمومی قاعدے کے طور پر موسوی
Page 91
79
مذهب کی تشکیل میں تین تخلیقی اصولوں کا کردار
شریعت میں عدل اور انتقام کا اصول ہی کارفرما ہے.جیسا کہ ہم بخوبی دیکھ سکتے ہیں کہ عضو کی شرط لفظ " احسان میں شامل ہے.چنانچہ احسان کو بکلی
نظر انداز نہ کرنے کے باوجود موسوی شریعت میں اسے وہ اہمیت حاصل نہیں جو سیحی تعلیمات میں دی
گئی ہے.اس حقیقت کے باوجود کہ حضرت عیسی علیہ السلام نے اس الزام کو کلیۂ رد فرمایا ہے کہ آپ
موسوی شریعت کو تبدیل کرنے آئے ہیں ( متی 17:5 و18 ) آپ علیہ السلام نے موسوی شریعت کے
ایک حکم یعنی انتقام کی بجائے دوسرے حکم یعنی عفو و در گزر پر زور دیا.لیکن جب آخری صاحب شریعت
نبی حضرت اقدس محمد مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت مذہبی ارتقا اپنے کمال کو پہنچ گیا تو انتہائی
ترقی یافتہ ، جامع اور متوازن تعلیم دی گئی جو عدل ، احسان اور ایتا عوذی القربی کے مابین حسین توازن
کو مضبوطی سے قائم کرتی ہے.حضرت نوح علیہ السلام کے ذکر کی طرف واپس آئیں تو عدل کی تعلیمات کے متعلق بہت سے
سوالات حل طلب ہیں.قرآن کریم کے مطالعہ سے یہ نتیجہ نکالنا چنداں مشکل نہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام
کی قوم میں فی الحقیقت عدل اور انصاف بالکل اٹھ چکا تھا اور ہر شعبہ زندگی میں ظلم وستم کا دور
دورہ تھا.سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ظالم قوم کو احسان کی تعلیم کے پیش نظر معاف کیا جاسکتا ہے؟ یا
عدل کا تقاضا ہے کہ ہر ظالم کو اس کے گناہوں کی سزادی جائے.یہ دوا ہم سوال سیر حاصل بحث
کے متقاضی ہیں.حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے مسلسل آپ علیہ السلام کے ساتھ تمسخر کیا، آپ علیہ السلام کی
تعلیمات کے انکار پر مصر رہے اور آپ علیہ السلام کے مشن کونا کام کرنے میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ
کیا.ان سب باتوں کے باوجود خدا کو یہ علم تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کیلئے رحم کی دعا کریں
گے.چنانچہ پیشتر اس کے کہ ان کی تباہی کی گھڑی آن پہنچتی ،اللہ تعالیٰ نے یہ بتا کر کہ اس قوم کی اصلاح کی
کوئی امید باقی نہیں رہی، حضرت نوح علیہ السلام کو ان کیلئے بخشش کی دعامانگنے سے منع فرما دیا.اللہ تعالیٰ
کے اس فیصلہ کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے حق میں دعا کی بجائے بددعا کی جس میں
بلا استثناء تمام منکرین شامل تھے.حتی کہ وہ یہ بھی نہ جانتے تھے کہ بدقسمتی سے ان کا حقیقی بیٹا بھی اس
بددعا کا شکار ہو جائے گا.یہ انکشاف ان پر اس وقت ہوا جب انہوں نے دیکھا کہ خود ان کا بیٹا بھی
غرق ہونے کو ہے.تب وہ حیرت سے پکار اٹھے : ” میرا بیٹا! میرا بیٹا! میرا خون! میرا خون!“.دراصل یہ خدا تعالی کا فیصلہ تھا کہ ایک ایسی مثال قائم کی جائے جس سے یہ الہی فیصلہ عبرت
Page 92
80
عدل، احسان اور ایتاء ذي القربى - حصه اول
کے ایک نشان کے طور پر ظاہر ہو اور آئندہ آنے والی نسلیں اس سے عظیم سبق سیکھیں.اس میں یہ سبق
دیا گیا ہے کہ جب عدل و انصاف کا وقت آجاتا ہے تو کوئی بھی انسانی رشتہ اس عمل میں دخل نہیں دے
سکتا.جب اللہ تعالیٰ ایک قسم کے ظالموں کو سزا دینے کا فیصلہ صادر فرما دیتا ہے تو پھر اس مخصوص طبقہ
سے تعلق رکھنے والے تمام افراد کے ساتھ یکساں سلوک کیا جاتا ہے اور کسی کو کسی دوسرے پر کوئی ترجیح
نہیں دی جاتی یہاں تک کہ انبیا علیہم السلام کے قریبی رشتہ داروں کو بھی نہیں چھوڑا جاتا.حضرت لوط علیہ السلام کو جس قوم کی طرف مبعوث فرمایا گیا وہ ہم جنس پرستی، کھلی کھلی بے حیائی
اور شاہراہوں پر ڈاکہ زنی جیسے جرائم میں ملوث تھی.اللہ تعالیٰ نے حضرت
ابراہیم علیہ السلام کو ان کے
حق میں دعا کرنے کی اجازت دی لیکن جب انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی تنبیہات پر کان نہ
دھرا اور اپنے گھناؤنے جرائم پر مصر رہے تو پھر خدا تعالیٰ نے ان کی تباہی کا فیصلہ کر لیا.حضرت ابراہیم
اور حضرت لوط کو آنے والے عذاب کی خبر دی گئی جس کے بعد سدوم اور گمورہ نامی بستیوں کے
باسیوں کا وجود ایک خوفناک زلزلہ کے باعث صفحہ ہستی سے مٹادیا گیا.یہاں اگر چہ انبیاء نے رحم مانگا
لیکن تقدیر الہی بد کرداروں
کو بخشنے کی بجائے اصول عدل کے عین مطابق سزاد ینے کا فیصلہ کر چکی تھی.اس کے برعکس حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے باوجود عذاب کی پیش گوئی کے بچا
لیا.ہوا یوں کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے آپ کا بکلی انکار کر دیا لیکن تباہی کا فیصلہ ہونے
پہلے پہلے آخری لمحات میں ان کے تو بہ کرنے پر اللہ تعالیٰ نے انہیں بخش دیا.اس سے ثابت ہوتا
ہے کہ اللہ تعالیٰ کے غضب کی تقدیر آخری لمحہ میں بھی ٹل سکتی ہے.لوگ اگر اپنی حالت میں تبدیلی کر
لیں تو تقدیر الہی بھی اس کے مطابق بدل جایا کرتی ہے.لیکن ایسا معاشرہ بہر حال تباہ و برباد کر دیا جاتا
ہے جہاں جرائم کا غلبہ ہو چکا ہو.تاہم اگر لوگ حقیقی تو بہ کر کے جرائم سے باز آجائیں تو رحمت باری
تعالیٰ سے حصہ پا کر یقیناً بخشے جاتے ہیں.لیکن اگر وہ اپنے گناہوں پر مصرر ہیں تو پھر خدا کے چنیدہ
انبیاء کی نمازیں اور دعا ئیں بھی انہیں تباہی سے نہیں بچا سکتیں.پس احکام عدل اس امر کے متقاضی نہیں کہ ہر ظالم کولا ز ما سزادی جائے.بلکہ رحمت اور بخشش
کا دروازہ کھلا رکھا جاتا ہے لیکن جب سفا کی حد سے بڑھ جائے تو احسان کرنا بے فائدہ ہو جاتا ہے.اس صورت میں انبیاء کی متضرعانہ التجائیں بھی ایسی بدکردار اقوام کو بدانجام سے نہیں بچاسکتیں.تعلیمات عدل کا ارتقا
مختلف ادوار میں مبعوث ہونے والے انبیاء کرام کے حالات کے مطالعے سے اس امر پر روشنی
Page 93
مذهب کی تشکیل میں تین تخلیقی اصولوں کا کردار
81
پڑتی ہے کہ عدل کی تعلیمات کس طرح اپنے ابتدائی مراحل سے ترقی کرتے کرتے کمال تام تک
پہنچیں اور جو آگے چل کر اسلامی شریعت کی بنیاد ٹھہر ہیں.قبل از میں ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کے چار بنیادی اصولوں پر گفتگو کی تھی جن
میں ہر شخص کو بنیادی ضروریات زندگی یعنی غذا، پانی ، مکان اور لباس کی ضمانت دی گئی ہے لیکن حضرت
نوح علیہ السلام کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی قوم مادی ترقی اور اعلیٰ تہذیب و
تمدن رکھنے کے باوجود اپنی اخلاقی عظمت کھو بیٹھی.انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی تعلیمات کو رد
کر دیا اور اس حد تک ظلم کے مرتکب ہوئے کہ خدا تعالیٰ کی تقدیر نے بلا استثناء تمام بدکاروں کو سزادینے
کا فیصلہ صادر فرما دیا.چنانچہ نہ تو کوئی امتیاز روا رکھا گیا اور نہ ہی کوئی عذر قبول کیا گیا اور تمام مکفرین و
مکذبین کو ہلاک کر دیا گیا.ان میں ایک کو بھی نہیں چھوڑا گیا حتی کہ خود اپنے بیٹے کیلئے آپ کی التجا کو بھی
قانون عدل کے منافی قرار دے دیا گیا.خدا تعالیٰ نے عدل کا یہی رستہ اختیار فرمایا تا کہ اس کی بنیاد
مضبوط ہو کیونکہ یہی وہ واحد بنیاد تھی جس پر آئندہ اعلیٰ اخلاق کے محل تعمیر ہونے تھے.حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے تک معاشرے میں عدل کی تعلیم اس مضبوطی سے
معاشرے میں قائم ہو چکی تھی کہ کوئی بڑے سے بڑا آدمی بھی اپنے اثر ورسوخ کو استعمال کرتے
ہوئے عدل کے تقاضوں کو نظر انداز کرنے کی جرات نہیں کرتا تھا.چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کو
مصر کے تمام خزانوں کے امین ہونے کے باوجود اتنا بھی اختیار نہیں تھا کہ اپنے بھائی کو بلا استحقاق
اپنے پاس روک لیں.موسوی شریعت میں عدل و انصاف پر اس قدر زور دیا گیا کہ احسان اور عفو و درگزر کی اہمیت
بظاہر بہت ہی کم دکھائی دیتی ہے.یہود کو بنی نوع انسان کے ساتھ آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت
کے بدلے دانت کی تعلیم دی گئی.اس کے برعکس حضرت عیسی علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو
دوسرا گال بھی پیش کر دینے کی تاکید فرمائی.چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عدل کی اہمیت
اور اپنے حقوق پر زور دیا جبکہ عیسائیت کی تعلیم نے احسان اور ایثار کے جذبے کو اتنا ابھارا کہ دوسری
انتہا پر جا پہنچی.بعض ادوار میں عدل پر زور دیا گیا اور بعض میں عدل کو قربان کئے بغیر احسان پر زور دیا گیا.تعلیم خواہ کوئی بھی ہو اصول عدل کی خلاف ورزی کہیں بھی نہیں ملتی.یادر ہے کہ ایثار، عدل کے منافی
ہرگز نہیں تاہم احسان کی خاطر دوسروں کے حقوق پامال کرنے کا کسی مذہب میں کوئی تصور نہیں مل
وو
Page 94
82
عدل، احسان اور ایتاء ذي القربى - حصه اول
سکتا.چنانچہ عیسائیت نے عفوو درگزر یا احسان کی خاطر دوسروں کے حقوق غصب کرنے کی ہرگز
اجازت نہیں دی.الغرض تمام آسمانی تعلیمات اپنے اپنے زمانہ کے تقاضوں سے مکمل طور پر ہم آہنگ رہی ہیں.حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کے مخصوص حالات کے تقاضوں کے پیش نظر
عدل اور مساوی بدلہ لینے پر زور دیا گیا جبکہ عیسوی دور کا بیمار معاشرہ ایک بالکل الگ قسم کے علاج کا
متقاضی تھا.اسی موازنے میں سلسلہ عدل کو دیکھا جا سکتا ہے جو ان دو مختلف ادوار کو باہم ملا رہا ہے.
Page 95
اسلام مذہبی تعلیمات کا منتهی
9- اسلام: مذہبی تعلیمات کا منتہی
اسلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ترقی یافتہ دور :
83
اب ہم اُس عظیم الشان دور کا ذکر کرتے ہیں جو نزول قرآن
کا دور ہے اور جس میں قرآن کریم کے
نزدیک مذہب کا ارتقا اپنے نقطہ عروج تک پہنچ گیا اور تعلیمات ہر پہلو سے مکمل ہو گئیں جیسا کہ فرمایا:
الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ
لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا (المائد 4:50)
ترجمہ: آج کے دن میں نے تمہارے لئے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر میں
نے اپنی نعمت تمام کر دی ہے اور میں نے اسلام کو تمہارے لئے دین کے طور پر
پسند کر لیا ہے.قرآن کریم نے عدل کے مضمون کو ہر شعبہ زندگی کے تعلق میں بیان فرمایا ہے.یہ ایک بہت
ہی دلچسپ اور وسیع مطالعہ ہے جس کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرنا تو سر دست پیش نظر نہیں لیکن اس حد
تک تفصیل ضروری ہے کہ قاری مضمون کو پوری طرح سمجھ لے اور وہ قرآن کریم کی جامعیت اور کمال
کے اس دعویٰ کو پوری طمانیت کے ساتھ قبول کر سکے.قرآن کریم اور بانی اسلام حضرت محمد مصطفے صلی
اللہ علیہ وسلم کا عدل کے سیاق و سباق میں ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَبُ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجًان
(الكيف 2:18)
ترجمہ: سب تعریف اللہ ہی کیلئے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب اتاری اور
اس میں کوئی کبھی نہیں رکھی.قرآن کریم کی کوئی تعلیم بھی بے مقصد نہیں ہے یعنی ساری کتاب کا ”الف“ سے لے کر
یا تک مطالعہ کر جاؤ عدل کے اس درمیانی رستے سے کوئی ذرہ بھر بھی بھی تم اس کتاب میں نہیں پاؤ
گے.یہ ایسی کتاب ہے جو کسی ایک قوم یا نظریے کی طرف جھکاؤ نہیں رکھتی بلکہ متوازن اور نوع
انسانی کیلئے ایک عالمگیر کتاب ہے.لَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجًا میں ” ، “ کی ضمیر چونکہ ”عبد“ یعنی خدا کے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
کی طرف بھی پھیری جاسکتی ہے اس لئے اس
کا دوسرا معنی یہ بنے گا کہ سب حمد اللہ ہی کیلئے ہے جس
نے اپنے ایسے بندے پر ایک کتاب اتاری جس میں
کسی قسم کی کوئی کبھی نہیں ہے.66 699
"
Page 96
84
عدل، احسان اور ایتاء ذي القربى - حصه اول
پھر اس مضمون کو مزید کھولتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ وہ رسول ہے جس کو ہم نے ساری
دنیا کی ہدایت کیلئے بھیجا ہے اس لئے اس کا نور کسی ایک قوم یا علاقے تک محدود نہیں ہے بلکہ تمام
بنی نوع انسان کیلئے ہے.چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ:
اللَّهُ نُورُ السَّمَوتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكُوةٍ فِيهَا مِصْبَاحُ
المِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِيٌّ يُوْقَدُ مِنْ
شَجَرَةٍ مُّبْرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا
يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِى اللَّهُ لِنُورِهِ
مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ
(النور36:24)
عليمه
ترجمہ: اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے.اس کے نور کی مثال ایک طاق کی سی ہے
جس میں ایک چراغ ہو.وہ چراغ شیشے کے شمع دان میں ہو.وہ شیشہ ایسا ہو گویا
ایک چمکتا ہوا روشن ستارہ ہے.وہ (چراغ ) زیتون کے ایسے مبارک درخت
سے روشن کیا گیا ہو جو نہ مشرقی ہو نہ مغربی.اس (درخت) کا تیل ایسا ہے کہ
قریب ہے کہ وہ از خود بھڑک کر روشن ہو جائے خواہ اسے آگ کا شعلہ تک نہ چھوا
ہو.یہ نور علی نور ہے.اللہ اپنے نور کی طرف جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے
اور اللہ لوگوں کیلئے مثالیں بیان کرتا ہے اور اللہ ہر چیز کا دائمی علم رکھنے والا ہے.پس بانی اسلام حضرت محمد مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی امتیازی شان کو اس آیت نے اللہ کے
نور کی تمثیل کے طور پر پیش فرمایا جو اپنے تعلقات اور ترجیحات میں نہ مشرق کی طرف جھکا ہوا ہے نہ
مغرب کی طرف اور اسی مضمون
کو مزید کھولتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سراج منیر بھی رکھا
گیا یعنی ایسا سورج جو سب کو برابر روشنی پہنچاتا ہے.سورج بظاہر منبع نور دکھائی دیتا ہے لیکن گہرے تدبر سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی روشنی دراصل اس
کے خالق کی عطا ہے جس سے صاف طور پر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ نور کا اصل مبداء ذات باری تعالیٰ ہی ہے اور
انبیائے کرام مخلوق خدا تک اس کا نور پہنچانے میں محض سورج کا کردار ادا کرتے ہیں.اجرام فلکی میں
روشنی کے بہت سے سرچشمے ہیں جن میں زمین کے حوالے سے سورج کو ایک منفرد مقام حاصل ہے
Page 97
اسلام مذهبی تعلیمات کا منتهی
85
جس کا عالمگیر کردار واضح اور نمایاں ہے.بعینہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ایسی ہمہ
گیر شخصیت کی حامل ہے جو بلا تمیز شرق و غرب سارے کرہ ارض کو بقعہ نور بنا رہی ہے.حضرت اقدس محمد مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات قرآنی تعلیمات کی مظہر کامل
دکھائی دیتی ہے اور ان دونوں میں کامل ہم آہنگی پائی جاتی ہے.چنانچہ جب ام المومنین حضرت
عائشہ صدیقہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی بابت استفسار کیا گیا تو آپ نے مختصر مگر نہایت
جامع جواب دیا:
كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مجسم قرآن تھے.(8)
جملہ اسلامی تعلیمات ہر پہلو کے اعتبار سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت کے مطابق
ہیں.جس طرح اسلامی تعلیمات میں ایک حسین توازن پایا جاتا ہے اور وہ اصول عدل ، احسان اور
ایتاً ء ذی القربی پرمبنی ہے بالکل اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے.راه اعتدال:
اسی طرح امت محمدیہ کی بحیثیت ایک قوم کے جو فطرت ہے وہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے عین مطابق ہے جیسا کہ فرمایا:
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ
وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا (البقرة 144:2)
ترجمہ: اور اسی طرح ہم نے تمہیں وسطی امت بنادیا تا کہ تم لوگوں پر نگران ہو
جاؤ اور رسول تم پر نگران ہو جائے.جس طرح بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب ہر قسم
کی کبھی اور جانبداری سے پاک اور درمیانی راہ پر قائم ہیں اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
امت بھی درمیانی راہ پر قائم اور افراط و تفریط سے پاک ہے.چنانچہ انتہا پسندی کی تبلیغ اور تقلید کرنے
والے نام نہاد اسلامی فرقوں کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے.عربی لفظ وَسُط “ کے معانی میں درمیانی رستہ کے علاوہ بہترین ہونے کا مفہوم بھی شامل
ہے.چنانچہ جب کسی انسان کیلئے لفظ وسط “ استعمال کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ
Page 98
86
عدل، احسان اور ایتاء ذي القربى - حصه اول
بے حد متوازن شخصیت کا مالک ہونے کے ساتھ ساتھ عظیم بھی ہے.پس اُمَّةً وَسَطاً“ کا یہ معنی بھی
بنے گا کہ یہ بہترین امت ہے.یہ بنیادی خصلت جس قوم میں پیدا ہو جائے اور وہ ہر حال میں وسطی
طریق اختیار کرنے والی ہو نیز اس کا جھکاؤ ایک طرف نہ ہو تو دوسری قومیں اسے عزت و وقار اور اعتماد
کی نظر سے دیکھتی ہیں لیکن کسی ایک طرف جھکاؤ رکھنے والی قوم کو ہرگز یہ حق نہیں مل سکتا کہ وہ دیگر
قوموں کے درمیان عدل و انصاف کی کرسی پر بیٹھے اور ان پر نگران مقرر کی جائے.پس اسلام کو ایک عالمگیر منصف کے طور پر پیش کرنا بالکل برحق ہے کیونکہ یہ وہ دین ہے جس
میں تمام بنی نوع انسان کا نگران بننے کی صلاحیت موجود ہے.اسی طرح امت کے اخلاق کی نگرانی
کیلئے اور اس امر کو یقینی بنانے کیلئے کہ یہ امت واقعی انصاف پر قائم ہے اس پر ایک ایسے رسول کو نگران
بنادیا گیا ہے جو صفت عدل میں درجہ کمال کو پہنچا ہوا ہے.آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدائے بزرگ و
برتر اور مالک کون و مکاں کا کامل اعتماد حاصل ہوا چنا نچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف مسلمانوں بلکہ
درج ذیل آیت کے مطابق تمام انبیاء پر بھی نگران قرار دیا گیا.صراط
فَكَيْفَ إِذَا جِتُنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيْدِ وَ جِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًان
مستق
(النساء 42:4)
ترجمہ: پس کیا حال ہو گا جب ہم ہر ایک امت میں سے ایک گواہ لے کر آئیں
گے اور ہم تجھے ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے.قرآن کریم مسلمانوں کیلئے جو راہ عمل تجویز کرتا ہے وہ نہ صرف بے حد متوازن اور معتدل ہے
بلکہ یہ اعلان بھی کیا گیا ہے کہ یہ راہ ہر ظاہری اور باطنی بجھی سے پاک ہے.دینِ اسلام کا مرکزی نکتہ
یہ ہے کہ اس
کی تعلیم بے حد متوازن اور تعصب سے کلیہ پاک ہے.چنانچہ اس مضمون کو واضح کرتے
ہوئے فرمایا:
قُلْ إِنَّنِي هَدْيِنِى رَبِّى إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ
إِبْرَهِيْمَ حَنِيفًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (الانعام 162:6)
ترجمہ: تو کہہ دے کہ یقیناً میرے رب نے مجھے سیدھے رستے کی طرف
ہدایت دی ہے.(جسے ) ایک قائم رہنے والے دین، ابراہیم حنیف کی ملت
( بنایا ہے ) اور وہ ہرگز مشرکین میں سے نہ تھا.
Page 99
اسلام مذهبی تعلیمات کا منتهی
87
یہ آیت صراط مستقیم کے معانی پر ایک نئے رنگ میں روشنی ڈال رہی ہے.یعنی صراط مستقیم
درمیانی راہ ہونے کے علاوہ استقلال اور ثابت قدمی کی صفت بھی اپنے اندر رکھتا ہے.مثلاً اِسْتَقَامَ
زید کے معنی ہیں کہ زید گرائے جانے اور غیر متوازن کرنے کی تمام تر کوششوں کے خلاف ڈٹا رہا“
جبکہ قام سے مراد صرف سیدھا کھڑارہنا ہے.قام اور اِسْتَقَامَ کا مصدر تو ایک ہی ہے لیکن جب قَامَ
کے شروع میں ”است“ کا اضافہ کیا جاتا ہے تو اس کے بنیادی معنوں میں ایک نئے مفہوم کا اضافہ
ہو جاتا ہے یعنی قدم اکھاڑنے اور غیر متوازن کرنے کی تمام بیرونی کوششوں کے باوجود ثابت قدم
رہنا اور تمام تر مخالف حالات کے باوجود پورے استقلال سے اپنے عقائد پر مضبوطی سے جمے رہنا.پس دشمن کے حملے جو صراط مستقیم سے ہٹانے کیلئے ہیں، کے مقابل پر مسلمانوں کو کہا گیا کہ وہ یہ دعا
کرتے رہیں کہ انہیں صراط مستقیم پر قائم رہنے کی طاقت ملتی رہے.پس صراط مستقیم ایسی راہ ہے جسے لوگ ٹیڑھا کرنے کی کوشش کریں گے مگر اللہ تعالیٰ نے اس
بات کا انتظام فرما رکھا ہے کہ اس راہ میں تبدیلی کی تمام کوششیں بالآخر ناکام ہو جائیں گی.ہرصدی
میں کم از کم ایک بار کسی انہی مصلح کے ذریعہ تجدید دین کا وعدہ اس امر کو یقینی بنا دیتا ہے کہ وقتاً فوقتاً
انسانی تحریف اور فطری کمزوریوں کی اصلاح ہوتی رہے گی.وسطاً کے حقیقی معنی یہی ہیں کہ جیسے
اسلام کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم کی کبھی اور جانبداری سے پاک ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
امت اور تعلیم بھی سیدھی اور جانبداری سے پاک ہے.یہ بات ذہن نشین رہنی چاہئے کہ صراط مستقیم کا تصور بھی مذہب میں بتدریج وسعت پذیر ہوا
ہے اور اس نے مختلف ادوار میں سے گزر کر انسانی ارتقا کے ساتھ ساتھ ترقی کی ہے.اسلام سے پہلے
مذاہب میں بھی صراط مستقیم کی اصطلاح پائی جاتی ہے، مثلاً مذکورہ بالا آیت کی رو سے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مذہب کو صراط مستقیم قرار دیتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے
دین کی طرف بھی یہی بات منسوب کرتے ہیں اور خود کو ان کی تعلیم سے ہم آہنگ بیان فرماتے ہیں.اب
سوال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صراط مستقیم اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صراط مستقیم
میں فرق کیا تھا ؟ در اصل فرق صرف درجے کا ہے اگر چہ مذہب کے آغاز سے ہی انسان
کو صراط مستقیم پر
چلایا گیا ہے لیکن اسلام سے پہلے کے تمام مذاہب مخصوص زمانے اور مخصوص قوم کیلئے آئے تھے.ان میں
سے کوئی مذہب بھی عالمگیر نہیں تھا.چنانچہ ان کیلئے صراط مستقیم کی اصطلاح کا اطلاق بھی مخصوص زمانی اور
قومی تقاضوں کے مطابق کیا گیا چنانچہ الہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے:
Page 100
عدل، احسان اور ایتاء ذي القربى - حصه اول
الَّذِينَ آمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَيْكَ لَهُمُ الْأَمْنُ
وَهُمْ مُهْتَدُونَ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا أَتَيْنَهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِةٌ
نَرْفَعُ دَرَجُتٍ مَّنْ نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمُ عَلِيْمٌ وَوَهَبْنَالَةٌ
اِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ كُلَّا هَدَيْنَا وَنُوْحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ
ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَن وَآتُوبَ وَيُوْسُفَ وَمُوسَى وَهَرُونَ
وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَ يَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلَّ
مِنَ الصَّلِحِينَ وَإِسْمَعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُوْنُسَ وَلُوْطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا
عَلَى الْعَلَمِينَ وَمِنْ أَبَا بِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ وَاِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَهُم
وَهَدَيْنَهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ (الانعام 83:6 تا88)
ترجمہ: وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو کسی ظلم کے ذریعے
مشکوک نہیں بنایا یہی وہ لوگ ہیں جنہیں امن نصیب ہوگا اور وہ ہدایت یافتہ
ہیں.یہ ہماری حجت تھی جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے خلاف عطا کی.ہم
جس کو چاہتے ہیں درجات میں بلند کر دیتے ہیں.یقینا تیرا رب بہت حکمت
والا ( اور ) دائمی علم رکھنے والا ہے.اور اس کو ہم نے اسحاق اور یعقوب عطا.کئے.سب کو ہم نے ہدایت دی اور نوح کو ہم نے اس سے پہلے ہدایت دی تھی
اور اس کی ذریت میں سے داؤد کو اور سلیمان کو اور ایوب کو اور یوسف کو اور موسیٰ
کو اور ہارون کو بھی.اور اسی طرح ہم احسان کرنے والوں کو جزا عطا کیا کرتے
ہیں.اور زکریا اور بیچی اور عیسی اور الیاس ( کو بھی).یہ سب کے سب صالحین
میں سے تھے.اور اسماعیل کو اور الیسع کو اور یونس کو اور لوط کو بھی.اور ان سب کو
ہم نے تمام جہانوں پر فضیلت بخشی.اور ان کے آباؤ اجداد میں سے اور ان کی
نسلوں میں سے اور ان کے بھائیوں میں سے ( بھی بعض کو فضیلت بخشی ) اور
انہیں ہم نے چن لیا اور صراط مستقیم کی طرف انہیں ہدایت دی.صراط مستقیم پر اسلام کی کوئی اجارہ داری نہیں ہے.درحقیقت اسلام سے پہلے بھی تمام انبیاء کو
88
Page 101
اسلام مذهبی تعلیمات کا منتهی
89
صراط مستقیم کی ہی تعلیم دی گئی تھی جیسا کہ مذکورہ بالا آیات میں یہی حقیقت بیان ہوئی ہے.پھر سوال
یہ ہے کہ ایک عالمگیر نبی کب دنیا میں آیا ؟ اور صراط مستقیم کا عالمی تصور پیدا کب ہوا؟ یہ بات سمجھنے کیلئے
ان قرآنی آیات کا مطالعہ مد ثابت ہوتا ہے جن میں اسلام اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمی اور
آفاقی حیثیت پر روشنی ڈالی گئی ہے.اس بارے میں قرآن
کریم فرماتا ہے:
وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ (الانبياء 108:21)
ترجمہ: اور ہم نے تجھے نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کیلئے رحمت کے طور پر.نیز فرمایا:
وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ
النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ
(29:34)
ترجمہ: اور ہم نے تجھے نہیں بھیجا مگر تمام لوگوں کیلئے بشیر اور نذیر بنا کر.مگر اکثر
لوگ نہیں جانتے.یہ بات خصوصاً قابل ذکر ہے کہ نزول قرآن تک قرآن کریم کے علاوہ کسی اور الہامی کتاب
نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ کسی عالمگیر پیغام اور شریعت کی حامل ہے اور نہ ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
سے پہلے کسی اور نبی نے تمام بنی نوع انسان کو مخاطب کرتے ہوئے بلا تمیز قوم اور ملت عالمگیر رسول
ہونے کا دعویٰ کیا ہے.آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی انبیا نے محض اپنی قوم کو مخاطب کیا ہے.زیادہ سے زیادہ انہوں نے ہمسایہ اقوام یا اپنی قوم میں رہنے والے غیر اقوام کے افراد کو اپنے مخاطبین
میں شامل کیا ہے.لیکن بنی نوع انسان کو بحیثیت مجموعی قرآن کریم کے سوا کسی نے مخاطب نہیں
کیا.اس لئے گزشتہ مذاہب میں صراط مستقیم کے معانی ان کی مخصوص ضروریات تک ہی محدود سمجھے
جانے چاہئیں.اسلام اور فطرت انسانی
یہ حقیقت واضح ہو جانے کے بعد کہ قرآن کریم وہ واحد الہامی کتاب ہے جس کا دعویٰ ہے کہ وہ
کل اقوام عالم اور سارے زمانوں کیلئے ہے، یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اس کی تعلیمات سب انسانوں پر
یکساں اطلاق پائیں گی.ان میں انسانی معاشرے کے کسی ایک حصے کو فوقیت دینے کا کوئی امکان
نہیں ہونا چاہئے اور نہ ہی اس کی تعلیم کسی ایک علاقے پر اطلاق پانی چاہئے.اسے زمان و مکان کی
Page 102
90
عدل، احسان اور ایتاء ذي القربى - حصه اول
تمام حدود و قیود سے بالا ہونا چاہئے.ورنہ اس کا آفاقی ہونے کا دعوی تسلیم نہیں کیا جاسکتا.اس پہلو سے جب ہم قرآن کریم کی تعلیم کا جائزہ لیتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی تعلیم اس
دعوے کی بھر پور تائید کرتی ہے.سب سے اہم اور بنیادی دلیل جو اس سلسلے میں پیش کی گئی ہے وہ یہ
ہے کہ دینِ اسلام فطرت انسانی سے کامل ہم آہنگی رکھتا ہے یعنی یہ وہ دین ہے جو کسی خاص دوریا
مخصوص قوم کو سامنے رکھ کر تشکیل نہیں دیا گیا بلکہ یہ فطرت انسانی سے پوری طرح مطابقت رکھتا ہے.ظاہر ہے کہ فطرت انسانی ہر جگہ ایک ہی رہتی ہے اور نسلی اور طبقاتی تقسیم اس پر اثر انداز نہیں ہوتی.اسی طرح بنیادی انسانی صفات وقت گزرنے کے ساتھ بھی تبدیل نہیں ہوتیں.آج سے دس ہزار
سال قبل کا پسماندہ انسان بھی وہی فطرت رکھتا تھا جو آج کا نسبتاً ترقی یافتہ انسان رکھتا ہے.قرآن کریم فرماتا ہے:
فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ
الدِّيْنُ الْقَيْمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (الروم 31:30)
ترجمہ: یہ اللہ کی فطرت ہے جس پر اس نے انسانوں کو پیدا کیا.اللہ کی تخلیق میں کوئی
تبدیلی نہیں.یہ قائم رکھنے اور قائم رہنے والا دین ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے.خدا تعالیٰ نے انسان کی فطرت کو جس سانچے میں ڈھالا ہے وہ تبدیل نہیں ہوتا.خدا تعالیٰ کی
پیدا کردہ ہر چیز کے معین خدو خال ہیں اور اس کی ایک خاص پہچان ہے.چنانچہ ہر نوع حیات، ہر
گروہ اور ہر صنف اسی قانون کے تابع ہے اور کوئی بھی اس سے مستی نہیں.جب تک کوئی نوع اپنی
تخلیق کے مخصوص مقصد تک محدود رہتی ہے، اس کے پاس اس طرز عمل پر چلنے کے سوا کوئی متبادل
رستہ نہیں ہوتا جو اس کیلئے بنایا گیا ہے.جب اس کا کردار بدلنا شروع ہوتا ہے تو یہ بھی نظام قدرت کی
خلاف ورزی نہیں ہوتی.دراصل بعض صفات میں تبدیلی کے اس تدریجی عمل کے ذریعے ادنی انواع
سے اعلیٰ انواع میں منتقلی کی تیاری ہورہی ہوتی ہے.یہ بھی فطرت کے نظام کا ایک حصہ ہے.اس
اعتبار سے بنیادی نظام میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی.ان معنوں میں جب تک انسان HOMO
SAPIEN میں شمار ہوتا ہے تب تک انہی جینیاتی خواص کا حامل رہے گا جو اس کے قدیم آبا ؤ اجداد
میں پائے جاتے تھے.پس اس نا قابل تغیر عالمگیر فطرت انسانی سے تعلق رکھنے والی مذہبی تعلیمات
بھی نا قابل تغیر ٹھہرتی ہیں.لہذا گزشتہ مذاہب اگر چہ تبدیل تو نہیں ہوئے لیکن ضروریاتِ زمانہ کے مطابق ان میں جزوی
Page 103
اسلام مذہبی تعلیمات کا منتهی
91
اصلاحات ہوتی رہی ہیں.پس اس بات کو خوب اچھی طرح سمجھ لینا چاہئے کہ اسلام دیگر مذاہب کورد
کر کے صداقت پر اپنی اجارہ داری قائم نہیں کرنا چاہتا بلکہ اس کے نزدیک خدا کا تصور تمام مذاہب
میں پایا جاتا ہے.مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ یہ بنیادی تعلیم اپنی مضبوطی اور حجم میں بڑھتی گئی اور اس کی
کئی شاخیں نکل آئیں جو اس مذہب کی ثانوی تعلیمات کی حیثیت رکھتی تھیں.پھر مذہبی ارتقا کے
ساتھ ساتھ ان ثانوی تعلیمات کا پھیلاؤ بنیادی تعلیم کی نسبت زیادہ ہو گیا.یہ شاخیں جو بنیادی تعلیم
سے پھوٹی تھیں تبدیل ہوتی رہیں لیکن بنیاد میں کوئی تغیر نہیں ہوا.قرآن کریم ایک ایسے مذہب کا
دعویدار ہے جو بنیادی فطرت کو قربان کئے بغیر انسانی کردار کے تمام ضروری پہلوؤں کا احاطہ کرتا
ہے.اس کے لئے دِین قيِّمة “ کی اصطلاح استعمال کی گئی ہے جس کے معنی دین برحق کے ہیں.نیز اس میں یہ مفہوم بھی شامل ہے کہ نہ صرف یہ اپنی ذات میں ایک سچا دین ہے بلکہ اپنے اندر یہ
طاقت بھی رکھتا ہے کہ دوسروں کو حق پر قائم کرے.مذہب تو خدا تعالیٰ کا وہ کلام ہے جو انسانی فطرت
پر نقش ہے اور تمام بنی نوع انسان خدا تعالیٰ کی فطرت کا ہی نقش اپنے اندر رکھتے ہیں.اسی مضمون کو
بیان کرتے ہوئے حضرت اقدس محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:
مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ
ترجمہ: ہر بچہ فطرت اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے.آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید فرماتے ہیں:
(9)
مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِدَانِهِ أَوْ يُنَصِرَانِهِ
أَوْ يُمَحِسَانِهِ.ترجمہ: ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے لیکن اس کے والدین اُسے یہودی یا عیسائی
ا
(10)
یا مجوسی بنا دیتے ہیں.اس
کا منطقی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ قرآن کریم اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک فطرت انسانی
اور دینِ اسلام ایک ہی چیز کے دو نام ہیں.تاہم ماں باپ بچے کا رخ جس طرف چاہیں موڑ سکتے ہیں.فرائڈ نے کئی الجھے ہوئے اور مخش نظریات دنیا کے سامنے پیش کئے جن میں سے کئی اب تک
غلط ثابت ہو چکے ہیں.وہ بالعموم مذہب کا اور خصوصاً اسلام کا مخالف تھا.مذہب کو بے وقعت کرنے
اور ہستی باری تعالیٰ کو رد کرنے کی کوشش میں اس نے یہ نظریہ پیش کیا کہ بچے کے مذہب کا اس کی
شخصیت پر کوئی اثر نہیں ہوتا.بچے کی پرورش اس رنگ میں بھی کی جاسکتی ہے کہ وہ دہریہ بن جائے
Page 104
92
عدل، احسان اور ایتاء ذي القربى - حصه اول
اور اسے کسی بھی قسم کا مذہبی انسان بھی بنایا جا سکتا ہے.اس کی تربیت اس طرح بھی کی جاسکتی ہے کہ
وہ اس پختہ یقین کے ساتھ بلوغت کی عمر میں داخل ہو کہ وہ خدا کا پیغمبر ہے.فرائڈ کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ اسلام اور خدا تعالیٰ کے خلاف یہ دلیل پیش کرتے ہوئے وہ بچے کی
پیدائش اور تربیت کے متعلق در حقیقت اسلامی نظریات کی ہی تائید کر رہا ہے.فرائڈ کے پیدا ہونے
سے بہت پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا چکے ہیں کہ ہر بچہ خدا تعالیٰ کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے
لیکن بعد ازاں والدین یا پرورش کرنے والوں کے زیر اثر سے کسی بھی شکل میں ڈھالا جا سکتا ہے.پھر اسی سے متعلق ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر انسانی فطرت یا ضمیر کی اصلیت کیا ہے؟
بہت سے مشہور فلسفی اور اہل عقل و دانش اس اصول پر متفق ہیں کہ دنیا میں ہر جگہ انسان کی فطرت پر
اخلاقی تعلیم کی ایک چھاپ ہے.یہ ایک ایسا نقش ہے جو کسی مخصوص مذہبی تعلیم کے زیر اثر پیدا نہیں
ہوا بلکہ اس فطری اخلاقی تعلیم کا شعور ہی دراصل ضمیر کہلاتا ہے.یہاں آٹھویں صدی کے مشہور فلسفی عمانوایل کانٹ کا ذکر کرنا مناسب ہوگا.اس نے بہت سے
ایسے دلائل کو ر ڈ کیا ہے جو مختلف لوگوں نے ہستی باری تعالیٰ کے اثبات میں پیش کئے ہیں.خاص طور
پر ایسلام (Anselm) کے ہستی باری تعالیٰ کے حق میں دلائل کی کانٹ نے پر زور تردید کی ہے.تاہم
جس چیز نے کانٹ کے اپنے ضمیر کو سوچنے پر مجبور کر دیا وہ یہی ہے کہ ہر انسان میں ایک اخلاقی شعور
پایا جاتا ہے.وہ کہتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی ہستی کے ثبوت میں صرف یہی دلیل قابل قبول ہے.(11)
یہ ضابطہ اخلاق در اصل انسانی ضمیر کا ایک حصہ ہے لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر شخص اس کو پورے
طور پر سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہو.آخری صاحب شریعت نبی حضرت اقدس محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم
پر جو وحی نازل ہوئی وہ اس فطرتی ضابطہ اخلاق پر روشنی ڈالتی ہے.کانٹ کا استدلال اپنے اندر وزن رکھتا ہے.اُس کے اس حقیقت کو سمجھ لینے سے کہ ہر
انسان کی فطرت میں خدا تعالیٰ کے تصور کی چھاپ موجود ہے.ہمارے ذہن میں قرآن کریم کی وہ
عظیم الشان آیت آتی ہے جس میں یہ ذکر موجود ہے کہ خدا کا تصور مخلوق کی فطرت کا جز ولا ینفک.ہے.یہ در حقیقت فطرتِ انسانی کے اس بنیادی خاکے میں شامل ہے جس نے انسانی ارتقا کے سفر
میں اس کا رہنما بنا تھا.چنانچہ قرآن کریم فرماتا ہے:
وَإِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي أَدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ
Page 105
اسلام مذہبی تعلیمات کا منتهی
وَ أَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ ۚ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوْا بَلَى شَهِدْنَا
أَنْ تَقُوْلُوْا يَوْمَ الْقِمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غُفِلِينَ (الاعراف 173:7)
ترجمہ: اور (یاد کرو) جب تیرے رب نے بنی آدم کی صلب سے ان کی نسلوں
(کے مادہ تخلیق ) کو پکڑا اور خود انہیں اپنے نفوس پر گواہ بنادیا اور پوچھا) کہ کیا
میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں ! ہم گواہی دیتے ہیں.93
مبادا تم قیامت کے دن یہ کہو کہ ہم تو اس سے یقینا بے خبر تھے.یہ آیت اس حقیقت کی تمثیلی رنگ میں وضاحت کر رہی ہے کہ کس طرح خدا تعالی پر ایمان
انسانی فطرت کے بنیادی خدو خال میں شامل ہے.احتساب اور موروثی گناہ:
اسلام نہ صرف افراد کے مابین بلکہ مختلف ادوار میں بھی کامل عدل کی تعلیم دیتا ہے.اسی اصول
کو اگر مذہبی تاریخ کے آئینے میں دیکھا جائے تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ہر زمانے میں خدا تعالیٰ
نے انسان کے ساتھ عدل کا ہی معاملہ فرمایا ہے.چنانچہ قرآن کریم فرماتا ہے:
تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ ۚ وَلَا
تُسْلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ (البقرة 135:2)
ترجمہ: یہ ایک امت تھی جو گزر چکی.اس کیلئے تھا جو اس نے کمایا اور تمہارے
لئے ہے جو تم کماتے ہو.اور تم اس کے متعلق نہیں پوچھے جاؤ گے جو وہ کیا
کرتے تھے.جہاں تک احتساب کا تعلق ہے تو ہر نسل اپنے اعمال
کیلئے اور ہر زمانہ اپنے طرز عمل کیلئے خود
جوابدہ ہے.یہ قرآنی طرز بیان مختلف ادوار میں انسان کی ارتقائی حالتوں کا تناسب ہم پر مزید کھول
دیتا ہے.چنانچہ بنی نوع انسان کا احتساب ان کی اپنی تاریخ کے مخصوص ادوار میں ان کی
استعدادوں کے مطابق ہوگا.وہ اپنی فطری صلاحیتوں کے مطابق اسی طرح پر کھے جائیں گے جس
طرح ہم اپنی استعدادوں کے مطابق.اس تناظر میں قرآنی تعلیمات وقت اور مقام دونوں اعتبار
سے اپنے اندر ایک آفاقیت رکھتی ہیں.انسانی فطرت ایسی عادلانہ تعلیم کو ہی الہی تعلیم گردانتی نیز انسانی اور خدائی تعلیمات کے مابین
Page 106
94
عدل، احسان اور ایتاء ذي القربى - حصه اول
تمیز کرنے کی بھی یہی ایک کسوٹی ہے.اس سلسلے میں موروثی گناہ کے عیسائی عقیدے کا مطالعہ بھی
نہایت دلچسپ ہے.یہ نہیں ہوسکتا کہ یہ عقیدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام
کو دیا گیا ہو.چنانچہ ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ حضرت عیسی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم
میں تحریف پولوس نے کی.بصورت دیگر وہ خدا نہایت درجہ عجیب وغریب ہو گا جو آدم علیہ الصلوۃ
والسلام کی ایک وقتی فروگزاشت پر آپ کو اور آپ کی آنے والی تمام نسلوں کو ہی ہمیشہ ہمیش کیلئے سزا
دیتا چلا جائے.اس سے ہمارا مقصد عیسائیت کی مذمت کرنا نہیں ہے بلکہ یہ دکھانا مقصود ہے کہ انسانی
ہاتھوں سے سچائی کو کس طرح مسخ کیا گیا ہے.موروثی گناہ کے عقیدے کے مختلف پہلوؤں کی بحث میں پڑے بغیر آئیے دیکھیں کہ قرآن کریم
کس طرح بیک جنبش قلم اس دعوی کو رد کرتا ہے.مذکورہ بالا آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم سے
تمہارے آباؤ اجداد کی بداعمالیوں کی بابت ہر گز نہیں پوچھا جائے گا.وہ صرف اپنے اعمال کے جوابدہ
ہوں گے اور تمہیں صرف اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہئے.چنانچہ قرآن کریم یہ اعلان فرماتا ہے کہ:
وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ
مِنْهُ شَيْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبى (فاطر 19:35)
ترجمہ: اور کوئی بوجھ اٹھانے والی (جان) کسی دوسری کا بوجھ نہیں اٹھائے گی اور
اگر کوئی بوجھ سے لدی ہوئی اپنے بوجھ کی طرف بلائے گی تو اس (کے بوجھ
میں) سے کچھ بھی نہ اٹھایا جائے گا خواہ وہ قریبی ہی کیوں نہ ہو.یہ آیت کریمہ کفارہ کے عقیدے کا رد کر رہی ہے.کفارہ یہ ہے کہ حضرت عیسی علیہ الصلواۃ
والسلام صلیب پر جان دے کر دوسروں کی بخشش کا باعث ہو گئے ہیں.مذکورہ آیت کریمہ یہ اعلان کر
رہی ہے کہ کسی موجودہ یا آئندہ نسل سے گزشتہ نسلوں کے گناہوں کا بوجھ اٹھانے کیلئے نہیں کہا جائے
گا.ایک فرد کا بوجھ کسی بھی صورت میں کسی دوسرے انسان پر نہیں ڈالا جاسکتا خواہ وہ اس بوجھ کو
اٹھانے کیلئے تیار بھی ہو.در حقیقت اسے انصاف کے ادنی تقاضوں کے خلاف قرار دیا گیا ہے کہ
کرے کوئی اور بھرے کوئی !
پس اگر انصاف کی ہی بحث ہے تو عہد نامہ جدید ( لوقا23:9) مندرجہ بالا قرآنی آیت کا مضمون
ہی بیان کرتا دکھائی دیتا ہے.یوں معلوم ہوتا ہے کہ بعد میں آنے والوں نے کفارہ کی جو کہانی
حضرت عیسی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کی تھی اس میں آپ علیہ السلام کا کوئی حصہ نہیں تھا.
Page 107
اسلام مذہبی تعلیمات کا منتهی
95
حضرت عیسی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم در حقیقت بنیادی طور پر قرآن
کریم کی تعلیم کی طرح ہی سادہ
رواضح تھی کہ انصاف کو انصاف کے محل پر اور بخشش کو بخشش کے مقام پر رکھا جائے.لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى کا واضح قرآنی اعلان جرم وسزا کے معاملہ میں ایک اہم پہلو
کو بیان کرتا ہے جو انسانی فطرت سے پوری طرح ہم آہنگ ہے.اس سے قبل ایک اور مضمون پر
روشنی ڈالتے ہوئے جو آیت پیش کی گئی تھی وہ موروثی گناہ کے عقیدے کو نہایت عمدگی سے رد فرما رہی
ہے.یہ نہ صرف انسان کو پیدائشی طور پر گناہ سے پاک قرار دیتی ہے بلکہ اس کی فطرت کو اللہ کی
فطرت سے مشابہ قراردے
کر بنی نوع انسان کے شرف اور مرتبہ کوبھی خراج تحسین پیش کر رہی ہے.یہاں وہی آیت دوبارہ درج کی جاتی ہے:
فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ
عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيْمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ
النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ
(الروم 31:30)
ترجمہ: پس (اللہ کی طرف) ہمیشہ مائل رہتے ہوئے اپنی توجہ دین پر مرکوز رکھ.یہ
اللہ کی فطرت ہے جس پر اس نے انسانوں کو پیدا کیا.اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی
نہیں.یہ قائم رکھنے اور قائم رہنے والا دین ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے.جہاں تک ماضی، حال اور مستقبل کا تعلق ہے تو مذکورہ بالا آیات ان تینوں زمانوں کے انسانوں
کے مابین مکمل تو ازن کی نہایت عمدہ تصویر پیش کر رہی ہیں.ہر انسانی نسل سے برابر سلوک کیا جائے
گا اور کوئی نسل بھی احتساب سے مستثنیٰ قرار نہیں پائے گی.ماضی، حال اور مستقبل کے مابین عدل کے
مسئلے کو بیان کرتے ہوئے قرآن کریم یہ ہدایت دیتا ہے:
يَايُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ
وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (الحشر 19:59)
ترجمہ: اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو! اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور ہر جان یہ نظر
رکھے کہ وہ کل کیلئے کیا آگے بھیج رہی ہے اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرو.یقیناً اللہ
اس سے جو تم کرتے ہو ہمیشہ باخبر رہتا ہے.آنے والی نسلیں اپنے بداعمالیوں کیلئے جواب دہ ہوں گی بالکل اسی طرح جیسے موجودہ اور
گزشتہ زمانے کے لوگ اپنے اعمال کیلئے جواب دہ ہوں گے.خدا تعالیٰ کے غضب اور اس کی سزا
Page 108
96
عدل، احسان اور ایتاء ذي القربى - حصه اول
کے لحاظ سے ہر نسل دوسری نسل سے الگ ہے.پہلوں کے گناہوں کا بوجھ آج کے لوگوں پر اور آج
کے لوگوں کے گناہوں کا بوجھ آنے والوں پر نہیں ڈالا جائے گا.عدل کی یہ حسین تعریف پولوس کی اس عیسائیت میں کہیں بھی نہیں ملتی جس پر آج عیسائیوں کی
اکثریت عمل پیرا ہے.حالانکہ حضرت عیسی علیہ السلام نے یہ تعلیم دی کہ ہر شخص اپنا بوجھ خود اٹھائے
گا جبکہ پولوس کے نقش قدم پر چلنے والے عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہر آئندہ نسل گزشتہ نسلوں کے تمام
گناہوں کا بوجھ اٹھائے گی.اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے:
فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلوةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَتِ
فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّان (مریم 60:19)
ترجمہ: پھر ان کے بعد ایسے جانشینوں نے (ان کی ) جگہ لی جنہوں نے نماز کو
ضائع کردیا اور خواہشات کی پیروی کی.پس ضرور وہ گمراہی کا نتیجہ دیکھ لیں گے.اگر نیک لوگوں کی اولا دا پنی عبادتوں سے غافل ہو جاتی ہے اور شہوات کی پیروی کرتی ہے تو ان
کے آبا و اجداد کی نیکی ان کے کسی کام نہیں آئے گی.جس طرح کوئی نسل گزشتہ نسلوں کے گناہوں کی سزا
نہ پائے گی اسی طرح آئندہ زمانے کے انسان کو گزشتہ لوگوں کے نیک اعمال کی جزا بھی نہیں ملے گی.قرآن کریم کے بغور مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآنی تعلیمات اتفاقی ، بے ربط اور بے جوڑ
نہیں ہیں بلکہ یہ ایک عظیم اور حسین نظام کا حصہ ہیں جو دراصل عدل کے قیام اور استحکام پر مبنی
ہے.اس میں تمام انسانوں کے ساتھ یکساں سلوک روا رکھا گیا ہے قطع نظر اس کے کہ وہ کس جگہ اور
کس زمانے میں پیدا ہوئے.تمام انسانوں کے بنیادی حقوق ایک جیسے ہی ہیں.مختلف افراد کے
مابین پائے جانے والے نسلی اور زمانی امتیازات کی بنیاد بھی عدل وانصاف پر ہے نیز مشرق ومغرب،
کالے گورے اور عربی عجمی کے مابین تمام تعلقات بھی عدل کے آفاقی اصول
پر ہی مبنی ہیں.اس عظیم الشان کامل اور حسین تعلیم کے متعلق بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ناخواندہ عرب
نے جو بکریاں چرایا کرتا تھا ، خود بنالی اور پھر اسے خدا کی طرف منسوب کر دیا.اس سے بڑھ کر جھوٹی
بات اور کیا ہو سکتی ہے.کسی زمانہ کا کوئی عالم آج تک ایسی حسین اور متوازن تعلیم کا عشر عشیر بھی دنیا
کے سامنے پیش نہیں کر سکا.بلکہ وہ تمام کتب جنہیں الہامی تسلیم کیا جاتا ہے یکجائی طور پر بھی ایسی
متوازن اور حسین تعلیم پیش نہیں کر سکتیں جو اسلام نے پیش کی.پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ عرب کے خشک
Page 109
اسلام مذہبی تعلیمات کا منتهی
97
ریگزار میں پیدا ہونے والا ایک اُمی اس گہری اور کامل حکمت کا سرچشمہ بن گیا؟ اپنی انہی اعجازی
خوبیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن کریم بار بار یہ دعویٰ فرماتا ہے:
قُل لَّبِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا
الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا
( بنی اسرائیل 89:17)
ترجمہ: تو کہہ دے کہ اگر جن و انس سب اکٹھے ہو جائیں کہ اس قرآن کی مثل
لے آئیں تو وہ اس کی مثل نہیں لاسکیں گے خواہ ان میں سے بعض بعض کے
مددگار ہوں.بلا شبہ آج تک کوئی اس چیلنج کا جواب نہیں دے سکا.بنی نوع انسان کیلئے ہدایت:
موروثی گناہ کی بحث کے بعد اب ہم مذہب کے ایک مثبت پہلو کو لیتے ہیں جو بنی نوع انسان
کیلئے خدا تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی کا تصور ہے.دنیا میں بہت سے ایسے مذاہب گزرے ہیں جو
کسی ایک قوم یا دور کے ساتھ مخصوص تھے.انہوں نے تاریخ انسانی میں اگر چہ بہت عظیم کردارادا کیا
لیکن ان کے کردار کی عظمت اور ان کا فیض صرف چند قوموں تک محد و در ہا اور ان کا زمانہ بھی محدود تھا
یعنی گزشتہ اقوام کو جو مذاہب اور تعلیمات دی گئی تھیں وہ تمام زمانوں
کیلئے نہیں تھیں.بدلتے ہوئے
حالات نئی تعلیمات کے متقاضی تھے.چنانچہ جب سابقہ تعلیمات کی ضرورت نہ رہی تو خدا تعالیٰ نے
انہیں تبدیل فرما دیا اور ان کی جگہ نئے دین کی بنیا د رکھ دی.مذہب کا از سر نو احیاء ہوا اور پھر ایک
عرصہ تک یہ تعلیمات ضرورتِ زمانہ کے اعتبار سے قابل عمل رہیں.مذاہب کا یہ وہ فلسفہ ہے جو بظاہر سادہ اور عام فہم ہے لیکن تعجب ہے کہ قرآن کریم کے سوا کسی
اور الہامی کتاب میں اس بچے فلسفے کا کوئی ذکر نہیں ملتا.دیگر تمام مذہبی کتب دنیا کے دوسرے
انسانوں سے کلیہ بے نیاز محض ایک قوم کا ذکر اس طرح کرتی ہیں گویا خدا نے ہدایت کیلئے صرف اسی
ایک قوم کو منتخب کر لیا تھا اور باقی سب اقوام نعوذ باللہ اس کے رحم سے محروم ہو کر رہ گئی تھیں اور ان میں
کوئی بھی فرستادہ مبعوث نہ ہوا جو انہیں ہدایت دیتا.اسلام کے سوا کسی اور مذہب نے یہ ذکر تک نہیں کیا کہ دیگر اقوام عالم یا زمانوں میں خدا تعالیٰ
کی طرف سے ہدایت اور رہنمائی نازل ہوئی تھی.یہ دعوئی خواہ کیسا ہی عجیب کیوں نہ دکھائی دے
Page 110
98
عدل، احسان اور ایتاء ذي القربى - حصه اول
بلا شبہ حق پر مبنی ہے اور آج بھی دیگر کتب سماویہ کا مطالعہ اس بیان کی صداقت کو تسلیم کرنے پر مجبور کرتا
ہے.صرف قرآن کریم ہی ہے جو ایک ایسے عالمگیر خدا کا تصور پیش کرتا ہے جو ہر ملک اور ہر زمانے
کے لوگوں سے ہمکلام ہوتا رہا ہے.چنانچہ جہاں تک مختلف اقوام کا تعلق ہے قرآن کریم فرماتا ہے:
وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ (الرعد 8:13)
ترجمہ: اور ہر قوم کیلئے ایک راہنما ہوتا ہے.بنی نوع انسان زمانی، جغرافیائی اور قومی اعتبار سے منقسم ہیں.قدیم زمانوں میں مملکت کی
شناخت ملکوں کی بجائے بستیوں اور شہروں کے ساتھ وابستہ تھی.قرآن کریم نہ تو قومی تفریق کرتا ہے
اور نہ ہی جغرافیائی.چنانچہ فرمایا:
وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنْذِرُونَ ذِكْرَى وَمَا
كُنَّا ظُلِمِينَ
(الشعراء210،209:26)
ترجمہ: اور ہم نے کوئی بستی ہلاک نہیں کی مگر اس کے لئے ڈرانے والے بھیجے
جاچکے ) تھے.( یہ ) ایک بڑا عبرتناک ذکر ( ہے ) اور ہم ہرگز ظلم کرنے والے
نہیں تھے.ذِکری کا ترجمہ یہاں نصیحت کیا گیا ہے لیکن اس لفظ کے اور بھی معانی ہیں.اس کے
ایک معنی دوسروں کیلئے سبق کے بھی ہیں.اسی طرح ایک معنی خدا تعالیٰ کی یاد کے بھی ہیں.پس انبیاء
کو محض نذ یرقرار نہیں دیا گیا بلکہ لوگوں کیلئے خوشخبریاں دینے والا بھی کہا گیا ہے جن کے نقش قدم پر چل
کر انسان خدا تعالیٰ تک پہنچ سکتا ہے.وہ یونانی دیو مالائی قصوں میں مذکورایسے ناصح نہیں تھے
جولوگوں کیلئے بدشگونی کا باعث ہوں اور ان ہلاکتوں سے بچنے کا کوئی موقع ہی میسر نہ ہو جن کی وہ خبر
دیتے تھے.بلکہ وہ تو نیک نصائح کرنے والے ایسے انبیاء تھے جو لوگوں کو گزشتہ اقوام کی تاریخ سے
سبق سکھاتے تھے.انہوں نے لوگوں کو اس امر کا قائل کرنے کی کوشش کی کہ گزشتہ اقوام کی تاریخ کی
روشنی میں وہ اپنے طرز عمل میں تبدیلی پیدا کریں.خدا کے یہ فرستادے محض ہلاکت اور تباہی کے
دروازے بند کرنے نہیں آئے تھے بلکہ در حقیقت نجات کے دروازے کھولنے آئے تھے.
Page 111
99
حوالہ جات حصہ اول
(1)
تفسیر حقانی.مولف: ابومحمد عبدالحق حقانی دهلوی تفسیر زیر آیت 65، سورة البقرة.جلد نمبر 1، صفحه 213.ناشر: نورمحمدکارخانه، تجارت کتب، کراچی.Out of My Later Years, by Albert Einstein, Philosophical Library,
New York and The Encyclopaedia of Religion, vol.5, Macmillan
Publishing Company, New York, pp.71-72.(2)
Grolier Encyclopedia, vol.6
(3)
Grolier Encyclopedia, vol.6
(4)
(5)
Textbook of Medical Physiology, Arthur C.Guyton, 5th Edition,
Saunders, 1976, Chap.78.صحيح مسلم.كتاب الاشربة.باب المومن ياكل فى معى واحد ، والكافر يأكل في سبعة امعاء.روایت نمبر 5375.تاليف: امام ابوالحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابورى.ناشر : دار السلام للنشر والتوزيع، الرياض.طبع اوّل: 1419ھ ، جولائی 1998 ء
Textbook of Medical Physiology, Arthur C.Guyton, 5th Edition,
Saunders, 1976, Chap.79.مسند احمد بن حنبل.جلد 6، ص91.تالیف: ابو عبدالله احمد بن حنبل.ناشر: دار الفكر.المعجم الكبير.جلد نمبر 1، صفحه 283 ، روایت نمبر 827.مولف: ابوالقاسم سلیمان بن احمد
الطبرانی ناشر: داراحیاء التراث العربي الطبعة الثانية.صحيح بخارى كتاب الجنائز، باب اذا اسلم الصبى فَماتَ، هَلى يُصلَّى عليه؟ روایت
نمبر 1358.مولف:ابوعبـدالـلـه مـحـمـد بن اسماعيل البخاري الجعفی.ناشر: دارالسلام
للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، ذو الحجة 1419ھ ، مارچ 1999ء
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
Critique of Pure Reason, by Immanuel Kant.Translated by J.M.D
Meiklejohn, J.M.Dent & Sons Ltd., 1978, pp.367-372 and Critique
of Judgment, by Immanuel Kant, Translated by James Creed
Meredith, Oxford University Press, 1986, pp.114-122.(11)
Page 113
عدل، احسان
اور
ايتاء ذى القربى
تین بنیادی متخلیقی اصول
حصه دوم
خطاب فرموده جلسہ سالانہ ربوہ پاکستان 27 دسمبر 1983ء
حضرت مرزا طاهر احمد
خليفة المسيح الرابع رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى
10- مذہب میں آزادی ضمیر
11 - اسلامی جہاد کے متعلق غلط نہی
12 عبادت میں عدل، احسان اور ایتا عذی القربیٰ کا مقام
13- عدل کا قیام بہر حال ضروری ہے
14- امانت اور احتساب
15 مسلمانوں اور غیر مسلموں کی ایک دوسرے کے خلاف شہادت
Page 115
جیسا کہ حصہ اول میں، جو پہلی تقریر پر مشتمل تھا بیان
کیا جا چکا ہے کہ عدل، احسان اور ایتاء ذی القربی
کے اصول نہ صرف تخلیق کائنات پر بلکہ زمین میں
زندگی کی تخلیق پر بھی یکساں اطلاق پاتے ہیں.ارتقا
کا سارا سفر انہی اصولوں کے تابع ہے جن سے
انسان سمیت کوئی بھی مستقلی نہیں ہے.
Page 117
مذہب میں آزادئ ضمیر
-10 مذہب میں آزادی ضمیر
105
قرآن کریم کی ایک آیت مذکورہ بالا اصولوں کے حوالے سے ایک بالکل نیا پہلو بیان کرتی ہے
جس کے مطابق انسان کے مذہب سے متعلقہ جملہ معاملات بھی انہی اصولوں کے تابع ہیں اور یہ کسی
ایک دور کے انسان کے مذہب تک محدود نہیں بلکہ در حقیقت یہ اصول ہر دور کے انسان سے انفرادی
اور اجتماعی طور پر تعلق رکھتے ہیں.آیت یہ ہے:
إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ الَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصْرِى وَالطَّبِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ
عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (البقرة 63:2)
ترجمہ: یقینا وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ جو یہودی ہیں اور نصاری اور دیگر الہی
کتب کے ماننے والے جو بھی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور
نیک اعمال بجالائے ان سب کیلئے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان
پر
کوئی خوف نہیں اور نہ وہ غم کریں گے.مسلمان مفسرین نے اس آیت کی مختلف تفاسیر پیش کی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس
کے مضمون کو پوری طرح سمجھ نہیں پائے جبکہ غیر مسلم مفسرین نے اس کے سیاق و سباق کو نظر انداز
کرتے ہوئے اس کی ایسی تفاسیر کی ہیں جن کا رویہ زیادہ تر متعصبانہ اور معاندانہ ہے.ان میں سے
بعض تو تکبر میں اس قدر بڑھ گئے ہیں کہ اس آیت کو اپنی منفی تنقید کا بطور خاص نشانہ بنایا ہے.ان
کے نزدیک یہ بنی نوع انسان کو اس فرض سے کلیہ آزاد کرتی ہے کہ وہ اسلام قبول کریں.ان کی تفسیر
کے مطابق نجات کے لئے صرف اللہ اور یوم آخرت پر ایمان اور نیک اعمال بجالانا کافی ہے قطع نظر
اس کے کہ آپ یہودی ہیں ، عیسائی ہیں یا صابی.صابی سے وہ شخص مراد ہے جو خدا تعالیٰ پر ایمان رکھتا
ہو اور دنیا میں کسی بھی جگہ نازل ہونے والی کسی بھی الہامی کتاب کا پیرو ہو.بالفاظ دیگر وہ یہ دعوی کرتے ہیں کہ اس آیت کے مطابق بنی نوع انسان کی نجات
کیلئے اسلام کو
مانا ہر گز ضروری نہیں بلکہ کسی بھی مذہب کی پیروی کر کے انسان کو نجات مل سکتی ہے.لیکن وہ اس بات
کو قطعی طور پر نہیں سمجھ پائے کہ یہ آیت ایک وسیع اور بہت گہرے مضمون پر مشتمل ہے جس کا اطلاق
ساری دنیا پر یکساں ہوتا ہے.اس کے معانی کو سمجھنے کیلئے قاری کو چاہئے کہ قرآن کریم کی اس سے ملتی
Page 118
106
عدل، احسان اور ایتاء ذى القربى - حصه دوم
جلتی دیگر آیات کی روشنی میں اس آیت کا مطالعہ کرے اور پھر ایک ایسا نتیجہ نکالے جوان آیات کے
معافی سے ہم آہنگ ہو.مضمون میں لچک کے اعتبار سے یہ آپ بغیر کوئی اندرونی تضاد پیدا کئے عمومی طور پر کئی قسم
کے
مختلف حالات پر چسپاں ہوتی ہے.اس کی صحیح تفاسیر میں کوئی باہمی تضاد نہیں ہوسکتا نہ ہی اس مضمون
سے متعلق دیگر آیات سے یہ متصادم ہو سکتی ہیں.لیکن اس نکتے کو پوری طرح سمجھنے کیلئے اس آیت کا
مختلف زاویہ ہائے نگاہ سے تفصیلی مطالعہ ضروری ہے.اولاً، جب ہم اس کا اطلاق زمانہ قبل از اسلام پر کرتے ہیں تو یہ آیت اس امر کی ایک بہترین
مثال ہے کہ کس طرح قرآن کریم دیگر تمام مذاہب کے ساتھ ایسے کامل عدل کا معاملہ کرتا ہے جس کی
نظیر کسی دوسری آسمانی کتاب میں نہیں پائی جاتی.یہ آیت نزول قرآن سے قبل ہر زمانے کے لوگوں کو
وعدہ دیتی ہے کہ قطع نظر اس کے کہ ان کا مذہب کیا ہے یا اسے کس نام سے موسوم کیا جاتا ہے، جب
تک وہ اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھیں گے اور اپنی مذہبی تعلیمات کے عین مطابق نیک
اعمال بجالائیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں امن و سلامتی اور نجات کی ضمانت دیتا اور یہ وعدہ کرتا ہے کہ نہ تو
انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے.چنانچہ جہاں تک گزشتہ مذاہب کا تعلق ہے تو ان سے وابستہ تمام لوگوں کو یہ آیت نجات کی
بشارت دے رہی ہے بشرطیکہ وہ پورے اخلاص کے ساتھ اپنی مذہبی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں اور جزا
سزا کے دن کے اٹل ہونے پر یقین رکھیں.اس آیت کے دوسرے پہلو کا اطلاق ان تمام لوگوں پر ہوتا ہے جنہوں نے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تو پایالیکن ان تک اسلام کا پیغام نہیں پہنچا.اس لحاظ سے انہیں بھی
پہلے ادوار کے لوگوں کے زمرے میں ہی شمار کیا جائے گا.ان کیلئے پیغام یہ ہے کہ:
تمام بنی نوع انسان جو دنیا کے کسی بھی گوشے میں بستے ہیں یہ یقین رکھیں کہ جب تک اسلام کا
پیغام ان تک پہنچ نہیں جاتا یا ایسے طریق پر نہیں پہنچتا کہ ان کیلئے اسے رد کر دینے کی کوئی گنجائش باقی
نہ رہے، تو اللہ تعالیٰ ان سے کسی قسم کی کوئی نا انصافی نہیں کرے گا.ان کے بارے میں کیا جانے والا
فیصلہ انہی کے مذہب کے مطابق ہوگا جیسا کہ سورۃ البقرۃ میں فرماتا ہے:
لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا (البقرة 2: 287)
ترجمہ: اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا.یعنی وہ انہیں بچائے گا اور ان
کا فیصلہ ان کے مذہب کے مطابق ہی کیا جائے گا.
Page 119
مذہب میں آزادئ ضمیر
107
اسی طرح اس آیت میں وہ لوگ بھی مخاطب ہیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عصر لیکن
دیگر مذاہب کے پیروکار تھے.اگر وہ اپنے اصولوں پر پورے صدق وصفا کے ساتھ کار بند اور اپنے
اپنے ایمان اور نیک اعمال پر ثابت قدم تھے تو یہ آیت انہیں بشارت دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اجر
ہرگز ضائع نہیں کرے گا.اس اعتبار سے جیسا کہ قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے، اعمالِ صالحہ کی جزا دو طرح پر دی جاتی
ہے.ایک تو اسی دنیا میں اور دوسری موت کے بعد کی زندگی میں.جہاں تک اول الذکر کا تعلق
ہے اس سے مراد یہ ہے کہ جیسے ہی ان تک اسلام کا پیغام پہنچتا ہے تو ان کے نیک اعمال اور مخلصانہ
ایمان کے نتیجہ میں ان سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ اسے قبول کر لیں گے.فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ “ میں ” أَجْرُ “ کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اعمال صالحہ کی وجہ سے ان کی
رہنمائی اسلام کی طرف کی جاتی ہے.اس معنی کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تائید حاصل ہے.چنانچہ حضرت حکیم بن حزام بیان کرتے ہیں کہ :
قبول اسلام سے
قبل میں بہت سے اچھے کام کیا کرتا تھا.مثلاً غریب پروری،
بھوکوں کو کھانا کھلانا اور مصیبت زدگان کی مدد کرنا وغیرہ.مشرف بہ اسلام
ہونے کے بعد ایک مرتبہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا
کہ اے اللہ کے رسول ( صلی اللہ علیہ وسلم)! مسلمان ہونے سے پہلے
میں نے جو نیک عمل کئے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ کیا ان کا اجر مجھے ملے گا؟ اس پر
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
تمہارا اسلام قبول کر لینا انہی کا تو اجر ہے.تمہارے نیک اعمال یقینا اللہ تعالیٰ
نے قبول فرمالئے ہیں“.(12)
آزادی ضمیر کے ایک پہلو کا جائزہ لینے کے بعد اب ہم اس کے ایک دوسرے پہلو کی طرف
آتے ہیں جس کا تعلق جبراً مذہب تبدیل کرنے کی مناہی سے ہے.قرآن کریم وہ واحد کتاب ہے جو دین کے معاملے میں مکمل اور غیر
مشروط آزادی ضمیر کی
علمبردار ہے.قرآن کریم غیر مذہبی لوگوں کی طرف سے مذہب پر لگائے جانے والے اس غلط الزام
کی سختی سے تردید کرتا ہے کہ مذاہب جبر کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں.چنانچہ فرماتا ہے:
لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرُ
Page 120
108
عدل، احسان اور ایتاء ذى القربى - حصه دوم
بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنَ بِاللهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى
لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (البقرة 2: 257)
ترجمہ: دین میں کوئی جبر نہیں.یقیناً ہدایت گمراہی سے کھل کر نمایاں ہو چکی.پس جو کوئی شیطان کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے تو یقیناً اس نے ایک
ایسے مضبوط کڑے کو پکڑ لیا جس کا ٹوٹا ممکن نہیں.اور اللہ بہت سنے والا ( اور )
دائمی علم رکھنے والا ہے.دین کے معاملے میں کسی قسم کا جبر جائز نہیں ہے.ہر شخص مکمل طور پر آزاد ہے.کسی مذہب
میں یہ اجازت نہیں دی گئی کہ کسی کا دین زبر دستی تبدیل کیا جائے اور نہ ہی یہ اجازت ہے کہ کسی شخص
کو اپنا مذہب چھوڑنے سے زبر دستی روکا جائے.مزید برآں یہ کہ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّینِ کا
اعلان فطرت انسانی کا ایک غیر مبدل قانون ہے یعنی اگر طاقت استعمال کی بھی جائے تو یہ دین کے
معاملے میں بے اثر ثابت ہوتی ہے کیونکہ طاقت کے بل بوتے پر دل و دماغ کو تبدیل نہیں کیا
جا سکتا.زبردستی ایسا کرنا بالکل بے سود ہے جس کا نتیجہ جبر و استبداد کے سوا کچھ نہیں نکلا کرتا.اس آیت میں تمام ادیان کیلئے طاقت کے استعمال کی کلی نفی کی گئی ہے کیونکہ ”دین“ کا لفظ عام
ہے جس کا اطلاق محض اسلام پر ہی نہیں بلکہ تمام ادیان پر یکساں ہوتا ہے.بظاہر تو بعض دوسرے
ادیان بھی طاقت کے استعمال کا انکار کرتے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ آیا ان کی الہامی کتب میں یتعلیم
اس قدر وضاحت سے موجود بھی ہے یا نہیں؟ میرا خیال ہے کہ اصولی طور پر ایسی تعلیم تمام الہامی کتب
میں مل سکتی ہے لیکن ممکن ہے کہ وہ اس قدر جامع نہ ہو بلکہ مقابلہ نہایت ابتدائی قسم کی ہو.یہ بھی عین
ممکن ہے کہ بعد کے پیروکاروں نے اپنے مقاصد کی خاطر اس میں
کئی باتیں شامل کر لی ہوں لیکن یہ
ایک الگ معاملہ ہے.جہاں تک قرآن کریم کا تعلق ہے تو وہ اس بنیادی قانون کو بیان کر کے خاموش
نہیں ہوجا تا بلکہ دیگر مذاہب کو بھی اس الزام سے بری الذمہ قرار دیتا ہے کہ انہوں نے اپنی تعلیمات کو
پھیلانے کی خاطر طاقت کا استعمال کیا تھا.قرآن کریم گزشتہ انبیا اور ان کی تعلیمات کا ذکر کرتے
ہوئے یہ اعلان کرتا ہے کہ وہ آزادی ضمیر کے علمبر دار تھے جبکہ ان کے بالمقابل ہمیشہ سے حق کی
مخالفت کرنے والوں نے جبر و استبداد کے ذریعے اسے دبانے کی کوشش کی.مذہب کی اس تاریخ سے جس کا نقشہ قرآن کریم نے کھینچا ہے، صاف طور پر عیاں ہوتا ہے کہ
جب سے اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی ہدایت اور رہنمائی کیلئے انبیا کا سلسلہ قائم فرمایا ہے تب سے
Page 121
مذہب میں آزادئ ضمیر
109
دو متضاد نظریات کے مابین ایک مستقل کشمکش جاری ہے.ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کے انبیا ہیں جنہیں
الہام کے ذریعے ہدایت ملتی ہے اور پھر وہ اپنی اپنی قوم کو اسی کی طرف بلاتے ہیں لیکن اس بات میں
ان کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ چاہیں تو اس پیغام کو قبول کر لیں اور چاہیں تو انکار کر دیں.وہ یہ اعلان
کرتے ہیں کہ نہ تو انہیںاپنی تعلیم کس پر زبردستی ٹھونسنے کا اختیار ہے اور نہ ہی وہ ایسا کرنے پر ایمان
رکھتے ہیں.جبکہ دوسری طرف ان کے معاندین ہوتے ہیں جو مسلسل نہ صرف جبر سے کام لینے کے
عقیدے کو ظاہر کرتے بلکہ دوسروں کو اپنے مذہب کی تبلیغ سے جبراً روکنے کا عملی مظاہرہ بھی کرتے
ہیں.وہ یہ دعوی کرتے ہیں کہ اگر تم دلائل کے ذریعے ہمارا مذہب تبدیل کروانے کی کوششوں سے
باز نہ آئے تو تمہیں اس کی سخت سزادی جائے گی اور ہم میں سے جو لوگ بھی نیا دین قبول کرنے کیلئے
ارتداد اختیار کریں گے تو ان کے ساتھ ایسا ظالمانہ سلوک کیا جائے گا کہ وہ عبرت کا نشان بن جائیں
گے.پس قرآن کریم کی رو سے ہر سچا نبی آزادی ضمیر کا ہی اعلان کرتا ہے جبکہ ہر جھوٹا مخالف
جبر واستبداد کا علمبردار ہوتا ہے اور سچائی کو طاقت کے ذریعے پھیلنے سے روکنے کی کوشش کرتا ہے.قرآن کریم نے اس کی بہت سی مثالیں پیش کی ہیں.حضرت شعیب علیہ السلام کے ذکر میں فرمایا:
قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يُشْعَيْبُ
وَالَّذِيْنَ أَمَنُوْا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ
كُنَّا كُرِهِينَ
(الاعراف 89:7)
ترجمہ: اس کی قوم کے ان سرداروں نے جنہوں نے استکبار کیا تھا کہا کہ اے
شعیب ! ہم ضرور تجھے اپنی بستی سے نکال دیں گے اور ان لوگوں کو بھی جو تیرے
ساتھ ایمان لائے ہیں یا تم لازماً ہماری ملت میں واپس آجاؤ گے.اس نے کہا
کیا اس صورت میں بھی کہ ہم سخت کراہت کر رہے ہوں؟
بالفاظ دیگر حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا گیا کہ اگر تم ہمارے مذہب سے
ارتداد اختیار کرو
گے تو ہم تمہیں اپنے ملک میں رہنے نہیں دیں گے.یہ سن کر آپ نے صرف اتنا فرمایا کہ ” کیا اس
صورت میں بھی کہ ہم نا پسند کرتے ہوں؟ حضرت شعیب علیہ السلام کا یہ پر مغز بیان آپ کے
معاندین کے چیلنج کا کمال پر حکمت اور فیصلہ کن جواب تھا.یہ امر بالکل واضح ہے کہ اگر کسی کا دل کسی مذہب سے متنفر ہو جائے تو جلا وطنی کی دھمکیاں اسے
Page 122
110
عدل، احسان اور ایتاء ذى القربى - حصه دوم
واپس پرانے مذہب میں نہیں لاسکتیں کیونکہ دھمکیاں لوگوں کو زیادہ سے زیادہ منافق تو بنا سکتی ہیں
لیکن ان کے باطنی عقائد کو ہرگز تبدیل نہیں کر سکتیں.لوگوں کو کسی مذہب میں زبردستی ہرگز داخل نہیں
کیا جاسکتا.لہذا انہیں سابقہ مذہب میں واپس لانے کا واحد ذریعہ یہی ہو سکتا ہے کہ اس مذہب کو رد
کرنے کی وجوہات کو منطقیانہ اور معقول دلائل سے دور کیا جائے کیونکہ مادی طاقت لوگوں کے عقائد
تبدیل نہیں کر سکتی.قرآن کریم بعض ایسے انبیا علیہم السلام کا ذکر بھی فرماتا ہے جن کے ساتھ ان کے معاندین کی
طرف سے یہی ناروا سلوک روا رکھا گیا.ہر جگہ اصل کہانی ایک ہی ہے.اس لحاظ سے قرآن کریم
میں مذکور انبیا میں حضرت نوح ، حضرت ابراہیم ، حضرت لوط ، حضرت ہود اور حضرت صالح علیہم
السلام شامل ہیں لیکن یہ فہرست یہیں ختم نہیں ہو جاتی.در حقیقت اس ضمن میں قرآن کریم نام لئے
بغیر سب انبیا کا عمومی ذکر فرماتا ہے اور واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ تاریخ کے کسی بھی دور میں پیدا
ہونے والے کسی بھی نبی کو کبھی دین میں جبر روا رکھنے کی اجازت نہیں دی گئی.چنانچہ باوجود سخت
تکالیف کے وہ بڑے استقلال کے ساتھ آزادی ضمیر کے بنیادی اصول پر کار بند رہے اور اگر کسی
جابر حکمران نے جبر دوسروں کا دین بدلنے کی کوشش کی بھی تو اس نے انہیں ہمیشہ عظیم قربانیاں دے
کر بھی اپنے بنیادی حقوق کی حفاظت کیلئے کمر بستہ پایا.ارتداد کے ”جرم“ پر بھی یہی حکم اطلاق پاتا ہے.اس ضمن میں مندرجہ ذیل قرآنی آیت
66
قابل توجہ ہے.وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ
لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمُ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّلِمِينَ
(ابراہیم 14:14)
ترجمہ: اور ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا اپنے رسولوں سے کہا کہ ہم ضرور تمہیں
اپنے ملک سے نکال دیں گے یا تم لازماً ہماری ملت میں واپس آجاؤ گے.تب ان
کے رب نے ان کی طرف وحی کی کہ یقینا ہم ظالموں کو ہلاک کر دیں گے.نیادین اختیار کرنے والوں کو اس مزعومہ ارتداد کے جرم میں ملک بدر کرنے کے علاوہ دیگر
سخت سزا میں بھی دی گئیں.حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دشمنوں نے اس ”جرم“ کیلئے نہ صرف
سزائے موت تجویز کی بلکہ اس پر عمل درآمد کا انتہائی سفاکانہ طریق اختیار کر کے انہیں زندہ جلا دینے
کا فیصلہ کرلیا.چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:
Page 123
مذہب میں آزادئ ضمیر
111
قَالُوْا حَرِقُوْهُ وَانْصُرُوا الِهَتَكُم إِنْ كُنْتُمْ فَعِلِينَ ( الا نبي 69:21)
ترجمہ: انہوں نے کہا کہ اس کو جلا ڈالو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم کچھ
کرنے والے ہو.فرعون نے بھی اس کا مذہب ترک کرنے والوں
کیلئے مختلف قسم کی نئی نئی اذیت ناک سزائیں
ایجاد کیں.اُس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دین اختیار کرنے والوں کو مندرجہ ذیل سزائیں دینے
کی دھمکی دی :
فَلَا قَطِعَنَ أَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُوصَلِّبَنَّكُمْ
فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَ أَبْقَى
(72:2046)
ترجمہ: پس لازماً میں تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ
دوں گا اور ضرور تمہیں کھجور کے تنوں پر سولی چڑھاؤں گا اور تم یقیناً جان لو گے کہ
ہم میں سے کون عذاب دینے میں زیادہ سخت اور باقی رہنے والا ہے.قرآن کریم کا بے مثال قانونِ عدل ہر قسم کے حالات پر یکساں اطلاق پاتا ہے.مذہبی
معاملات میں جبر کے تصور کو کلیۂ رد کرنے کے بعد یہ قانون تمام انبیا کو اس الزام سے بری قرار دیتا
ہے کہ انہوں نے لوگوں کو جبراً اپنے مذہب میں شامل کیا اور یوں انبیا کو یہ حق دیتا ہے کہ اس معاملے
میں ان کے ساتھ بھی انصاف کا سلوک کیا جائے.سب سے مضبوط دلیل جو قرآن کریم اللہ تعالیٰ یعنی خالق کا ئنات کے حوالے سے پیش فرماتا
ہے یہ ہے کہ اگر وہ چاہے تو حق قبول کرنے پر لوگوں
کو مجبور کر سکتا ہے کیونکہ وہ صحیح اور غلط کے مابین
انتخاب کے متعلق کوئی جھگڑا پیدا کئے بغیر بآسانی ایسا کر سکتا ہے.صحیح اور غلط کی موجودگی اور دونوں
میں سے ایک کو چن لینے کا انسانی اختیار، در اصل اس بات کا ناقابل تردید ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے
تشکیل دیئے ہوئے نظام کائنات میں جبر کی کوئی گنجائش نہیں ہے جیسا کہ فرمایا:
وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَا مَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ
النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (یونس 100:10)
ترجمہ: اور اگر تیرا رب چاہتا تو جو بھی زمین میں بستے ہیں اکٹھے سب کے سب ایمان
لے آتے تو کیا تو لوگوں کو مجبور کر سکتا ہے حتی کہ وہ ایمان لانے والے ہو جائیں.
Page 124
112
عدل، احسان اور ایتاء ذى القربى - حصه دوم
بعض مسلم علماء کا یہ موقف ہے کہ اگر چہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل کسی بھی نبی کو دین
کے معاملے میں جبر روا ر کھنے کا اختیار نہیں دیا گیا تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار دیا گیا تا کہ
دیگر تمام انبیاء پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور فضیلت ثابت ہو.ظاہر ہے کہ اس دلیل سے تو
اس کے برعکس بات ثابت ہوتی ہے کیونکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کم درجے کے حامل انبیاء
آزادی ضمیر کے علم بردار ہیں تو عقل یہ تقاضا کرتی ہے کہ حضرت اقدس محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو
ان سب گزشتہ انبیاء کی نسبت اس علم کو سب سے زیادہ بلند کرنا چاہئے.انبیاء علیہم السلام میں بہترین
نبی کا بنی نوع انسان کی آزادی کو سلب کر لینا، ان پر ایک احمقانہ الزام ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم کی بے داغ شخصیت کی توہین ہے.قرآن کریم اس کی تردید کرتے ہوئے فرماتا ہے:
فَذَكِّرُ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكَّرَةٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَّيْطِرِ إِلَّا مَنْ تَوَلَّى
وَكَفَرَ فَيُعَذِّبُهُ اللهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَتْ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ
عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ
(الغاشية 22:88 تا 27)
ترجمہ: پس بکثرت نصیحت کر.تو محض ایک بار بار نصیحت کرنے والا ہے.تو ان
پر داروغہ نہیں.ہاں وہ جو پیٹھ پھیر جائے اور انکار کر دے.تو اسے اللہ سب
سے بڑا عذاب دے گا.یقیناً ہماری طرف ہی ان کا لوٹنا ہے.پھر یقینا ہم پر ہی
ان کا حساب ہے.اس غیر مبدل قانون کے پیش نظر کسی بھی نبی نے لوگوں کو جبراً نیکی کی راہ پر نہیں چلایا.پس وہ
سب لوگ جو نیکی یا خدا کے نام پر اس کی خلاف ورزی کی جرات کرتے ہیں وہ جعلی خداؤں کی مانند
مستر د کئے جانے کے لائق ہیں کیونکہ ان کا کردار خدا تعالیٰ کے عاجز بندوں کے کردار کے برعکس ہے.کوئی بھی سچاند ہب آزادی ضمیر کے خلاف اپنے نام پر ہونے والے جرائم کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا
جاسکتا.ذمہ دار تو دراصل وہ نام نہاد ملاں ہیں جو نا انصافی کرتے ہوئے اپنے مقاصد کی خاطر اور
خدا تعالیٰ کی منشا کے برخلاف آسمانی تعلیمات میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں.حتی کہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ
زندگی کو تلف کرنے کا اختیار بھی بزعم خود ہی حاصل کر لیتے ہیں.قرآن کریم ایسے تمام مذاہب کے
دفاع میں کھڑا ہے اور ان تمام غلط الزامات سے ان کو بری الذمہ قرار دیتا ہے جو بعد کے ادوار میں
آنے والے علماء سو نے عائد کئے تھے.
Page 125
اسلامی جهاد کے متعلق غلط فهمی
11 - اسلامی جہاد کے متعلق غلط فہمی
113
آزادی ضمیر کے متعلق اسلام کے بالکل واضح اور غیر مبہم اعلان کا جائزہ لینے کے بعد ہمیں اس
کے اور اسلامی جہاد کے مابین بظاہر نظر آنے والے تضاد کوحل کرنا ہے.ذرا غور فرمائیے کہ یہ کس قسم کا
انصاف ہوگا کہ ایک طرف تو آزادی ضمیر کا غیر مشروط پر چار کیا جائے جبکہ دوسری طرف مسلمانوں کو
دنیا کے دیگر مذاہب اور اقوام کے خلاف ، اس امر کیلئے جس کو یہ حق سمجھتے ہیں، تلوار اُٹھانے کی
ضرورت پڑ جائے.اس مسئلے کو سمجھنے کیلئے ہم قارئین کی توجہ مندرجہ ذیل قرآنی آیت کی طرف مبذول کرواتے ہیں :
أَذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقْتَلُوْنَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللهَ عَلَى نَصْرِهِمْ
لَقَدِيرُ الَّذِيْنَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا
رَبُّنَا اللهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ
صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوتُ وَ مَسجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللهِ كَثِيرًا
وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزُ (الج 4140:22)
ترجمہ: ان لوگوں کو جن کے خلاف قتال کیا جا رہا ہے (قتال کی ) اجازت دی
جاتی ہے کیونکہ ان پر ظلم کئے گئے اور یقیناً اللہ ان کی مدد پر پوری قدرت رکھتا
ہے.( یعنی ) وہ لوگ جنہیں ان کے گھروں سے ناحق نکالا گیا محض اس بنا پر کہ
وہ کہتے تھے کہ اللہ ہمارا رب ہے.اور اگر اللہ کی طرف سے لوگوں کا دفاع ان
میں سے بعض کو بعض دوسروں سے بھڑا کر نہ کیا جاتا تو راہب خانے منہدم کر
دیئے جاتے اور گرجے بھی اور یہود کے معابد بھی اور مساجد بھی جن میں
بکثرت اللہ کا نام لیا جاتا ہے.اور یقیناً اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا جو اُس کی
مدد کرتا ہے.یقینا اللہ بہت طاقتور ( اور ) کامل غلبہ والا ہے.یہ آیات جہاد بالسیف سے متعلق اسلامی احکامات کیلئے نہایت اہم اور بنیادی حیثیت کی حامل
ہیں.انہی آیات کے نزول پر مسلمانوں کو پہلی مرتبہ تلوار اٹھانے کی اجازت ملی.یہ آیات واضح طور
پر ان ضروری شرائط کا ذکر کر رہی ہیں جن کے تحت مسلمانوں کو جہاد بالسیف کی نہ صرف اجازت ملی
بلکہ در حقیقت انہیں اس کا حکم دیا گیا ہے.ان آیات کا سرسری سا مطالعہ بھی یہی ثابت کرتا ہے کہ تلوار
Page 126
114
عدل، احسان اور ایتاء ذى القربى - حصه دوم
اٹھانے کی اجازت حملہ کی غرض سے نہیں بلکہ محض دفاع کی خاطر دی گئی ہے.بنیادی طور پر جہاد سے مراد کوئی مسلح جدو جہد نہیں ہوتی.مندرجہ بالا آیات میں دفاعی جدوجہد کو
بھی جہاد کی بجائے قتال کے نام سے موسوم کیا گیا ہے اور یہ اصطلاح اس وقت اطلاق پاتی ہے جب
دو حریف با ہم برسر پیکار ہوں.مسلمانوں کو اپنے دفاع میں وہی ہتھیار استعمال کرنے کی اجازت دی
گئی ہے جو ان کے حقوق کو غصب کرنے کیلئے ان کے خلاف استعمال کئے جاتے ہیں.یہ آیات بتا
رہی ہیں کہ وہ پہلے سے ہی جارحیت کا نشانہ بنے ہوئے تھے یہاں تک کہ انہیں ان کے گھروں سے
بھی نکال دیا گیا اور لمبے عرصے تک انہیں اس جارحیت کا سامنا کرنا پڑا حالانکہ انہوں نے ایسی کوئی
حرکت نہیں کی تھی جو دشمنوں کیلئے حملہ کرنے کی وجہ فراہم کرتی سوائے ان کے اس دعوے کے کہ اللہ
ہمارا رب ہے.چنانچہ کوئی بھی باشعور انسان بآسانی یہ مشاہدہ کر سکتا ہے کہ اس سارے ظلم وستم کے
بعد جب انہیں اپنے دفاع کی اجازت دی گئی تو اسے ہرگز جارحیت نہیں کہا جاسکتا.جس حکمت کی بنا پر مسلمانوں کو دفاعی جنگ کی اجازت دی گئی ہے اسی حکمت کی وجہ سے ان تمام
مذاہب کو اس کی اجازت دی گئی ہے جن کے پیغام کو بزور شمشیر دبانے کی کوشش کی گئی.یہ دراصل ایک
اعلان ہے جس سے یہ بات بخوبی واضح ہو جاتی ہے کہ یہ بنیادی حق تمام مذاہب کو یکساں طور پر دیا گیا
ہے.چنانچہ اگر اللہ تعالی بعض لوگوں کو اپنی عبادت گاہوں کی حفاظت کیلئے ہتھیا راٹھانے کی اجازت نہ
دیتا تو نہ صرف مساجد بلکہ گرجے اور یہودیوں کی عبادت گاہیں بھی مسمار کر دی جاتیں.مذکورہ بالا آیات کی روشنی میں بلا خوف تردید یہ کہا جاسکتا ہے کہ صرف اسلام ہی ایسا مذ ہب ہے
جو آزادی ضمیر کے بنیادی انسانی حق کی حفاظت کرتا ہے.اسے جہاد کہیں یا قتال لیکن یہ حق صرف
مسلمانوں کے ساتھ ہی مخصوص نہیں ہے.ہاں مسلمانوں کو اس آیت میں متنبہ ضرور کیا گیا ہے کہ وہ
دیگر اقوام و مذاہب کی عبادت گاہوں کا احترام قائم کئے بغیر اللہ تعالیٰ کے خاص فضلوں کے وارث
ہرگز نہیں بن سکتے ورنہ ان کا یہ حق قائم نہیں رہے گا کہ ان کی عبادت گاہوں کا احترام کیا جائے.وہ
دوسروں کی عبادت گاہوں کا احترام کر کے ہی اپنے اس حق کے مستحق بن سکتے ہیں.مندرجہ بالا آیات نہ صرف عدل کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہیں بلکہ احسان کے زمرے میں داخل
ہیں جس سے مراد یہ ہے کہ عدل کے تقاضوں سے آگے بڑھ کر دوسروں کے ساتھ حسن و احسان کا
معاملہ کیا جائے.اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی عبادت کا رنگ خواہ کتنا ہی تکلیف دہ کیوں نہ ہو پھر
بھی ایک حقیقی مسلمان کا فرض ہے کہ نہ صرف ان کے ساتھ عزت واحترام سے پیش آئے بلکہ جب
Page 127
اسلامی جہاد کے متعلق غلط فهمی
115
ان کی عبادت گاہوں پر حملہ ہو تو ان کا دفاع کریں.یہ پہلو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات
سے واضح ہوتا ہے جو آج بھی سینا پہاڑ پر سینٹ کیتھرائن کی خانقاہ میں یوں محفوظ ہے:
وشمن کے حملوں سے عیسائی گرجوں، خانقاہوں اور مزاروں کی حفاظت کرنا
تمام مسلمانوں پر فرض ہے.اس سے پہلو تہی کرنے والا اللہ تعالیٰ کا نافرمان اور
اس کے احکام کی خلاف ورزی کرنے والا شمار ہوگا اور اپنے مذہب یعنی اسلام
(13)،،
کیلئے بدنامی کا باعث ہوگا.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ دیگر مذاہب کے ساتھ
احسان سے بھی بڑھ کر ایتا و ذی القربی کا سلوک کریں.حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بنی
نوع انسان سے اس سے بھی بڑھ کر محبت رکھتے تھے جتنی کہ ماں اپنے بچے سے رکھتی ہے.چنانچہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف بنی نوع انسان کے بنیادی حقوق کے قیام کے عظیم جہاد کا
جھنڈا بلند کیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہیں بڑھ کر محبت ، رافت اور رحمت کا نمونہ دکھایا.خواہ کیسے ہی حالات کیوں نہ پیش آجائیں، ایک مسلمان کو ہرگز یہ اجازت نہیں کہ وہ دوسروں
سے زیادتی کرے.کسی مجرم کو معاف کر دینا اس سے
کہیں بہتر ہے کہ کسی معصوم کو سزا دے دی جائے.حیرت کی بات تو یہ ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر جبکہ مسلمان انتہائی کمزوری کے عالم میں تھے،
بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشہور جنگجو پہلوان کی طرف سے مدد کی پیشکش ٹھکرا دی تھی،
حالانکہ مسلمانوں کو اس کی اشد ضرورت تھی.چنانچہ ایک مشہور مشرک جنگجو نے مسلمانوں کی طرف
سے ہو کر لڑنے کی پیش کش کی تو صحابہ خوشی سے پھولے نہ سمائے لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ فرماتے ہوئے اس کی پیشکش ٹھکرا دی کہ راہ مولیٰ میں وہ کسی بھی کافر سے مدد لینے کے روادار نہیں
ہیں.چنانچہ اس شخص نے فوراً کلمہ شہادت پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیا.صاف ظاہر تھا
کہ اس نے ایسا صرف لڑائی میں شمولیت کی غرض سے کیا ہے.لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس کی نیت پر شک کئے بغیر اس کا یہ دعویٰ قبول فرمالیا.حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حقیقت کو
بخوبی جانتے تھے کہ وہ کسی ذاتی انتقامی جذبے کی تسکین کی خاطر مسلمانوں کے ساتھ مل کر قریش مکہ
کے خلاف لڑنا چاہتا ہے.اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دائرہ اسلام میں قبول فرمالیا
کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اس غیر متزلزل اصول پر قائم تھے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی دلوں کا حال
جانتا ہے.چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ بنیادی حق عطا فرمایا کہ وہ جو بھی دین رکھتا ہے
اس کا اعلان کر سکتا ہے.
Page 128
116
عدل، احسان اور ایتاء ذى القربى - حصه دوم
ہر
قسم کے حالات میں یہی اصول ایک منافق کے طرز عمل پر بھی اطلاق پاتا ہے.اس مضمون کو
سورۃ المنافقون کی مندرجہ ذیل ابتدائی آیات میں خوب کھول کر بیان کیا گیا ہے:
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِذَا جَاءَكَ الْمُنْفِقُونَ قَالُوا
نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللهِ وَ اللهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللهُ يَشْهَدُ
اِنَّ الْمُنْفِقِينَ لَكَذِبُونَ اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا
عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُوْنَ )
(المنافقون 1:63 تا 3)
ترجمہ: اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا ، بن مانگے دینے
والا ( اور ) بار بار رحم کرنے والا ہے.جب منافق تیرے پاس آتے ہیں تو
کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ ضرور تو اللہ کا رسول ہے.اور اللہ جانتا ہے کہ
تو یقینا اس کا رسول ہے.پھر بھی اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق یقینا جھوٹے ہیں.انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے.پس وہ اللہ کے راستے سے روکتے
ہیں.یقیناً بہت برا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں.یعنی وہ اپنے اس دعوے کے لبادے میں اپنے منافقانہ بد ارادوں کی تکمیل چاہتے ہیں.اول
یہ کہ جنگ کے سنگین حالات میں اپنے تئیں مسلمانوں سے محفوظ رکھ سکیں.دوم یہ کہ خود کو مسلمان ظاہر
کر کے سادہ لوح مسلمانوں کو گمراہ کر سکیں.لیکن اس کے باوجود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ
اجازت نہیں دی گئی کہ ان کو اس بات کا دعویٰ کرنے کے بنیادی حق سے محروم کر دیں جو در حقیقت ان
کے دلوں میں موجود نہ تھا.انہیں پھر بھی یہ حق دیا گیا کہ وہ خود کو مسلمان کہیں.آج ہم دنیا کے مختلف مسلم ممالک میں یہ تضاد دیکھتے ہیں کہ وہاں نہ صرف دین کے معاملہ میں
جبر کی تعلیم دی جارہی ہے بلکہ اس پر سختی سے عمل درآمد بھی کیا جا رہا ہے.ملاں دیکھتے ہیں کہ ایک شخص
خود کو مسلمان کہتا، کلمہ پڑھتا اور دیگر مسلمانوں کی طرح قبلہ رو ہو کر نماز بھی ادا کرتا ہے پھر بھی وہ اسے
دائرہ اسلام سے خارج قرار دیتے ہیں.ان کے نزدیک کسی کو ز بر دستی ان کے دین سے منحرف کر دینا
نیکی کا کام ہے حالانکہ در حقیقت یہ قرآن کریم کی واضح تعلیمات اور حضرت اقدس محمد مصطفے صلی اللہ
علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے کھلی کھلی بغاوت کے مترادف ہے لیکن انہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے.جز اسرا کے دن یہ لوگ اللہ تعالیٰ کا سامنا کس طرح کریں گے؟ انہیں تو شاید اس بات کی چنداں پر واہ
Page 129
اسلامی جہاد کے متعلق غلط فهمی
117
نہ ہو لیکن اللہ تعالیٰ کو تو یقینا ہے.درج ذیل حدیث اس دعوے کی مزید تائید کرتی ہے.حضرت اسامہ بن زید بیان کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک جنگ پر
روانہ فرمایا.راستہ میں ایک ایسے کافر سے ہماری مڈ بھیڑ ہوگئی جو جنگل میں چھپا رہتا اور جب کبھی کہ
مسلمان
کو تنہا پاتا تو حملہ کر کے اسے شہید کر دیتا تھا.بالآخر جب میں نے اس پر قابو پالیا اور اسے قتل
کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے فوراً کلمہ توحید لا اله الا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ پڑھ لیا یعنی اللہ
کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اُس کے رسول ہیں.بالفاظ دیگر اس نے اپنے مسلمان
ہونے کا اعلان کر دیا.تاہم میں نے اُس کے اس دعوے کو تسلیم نہ کیا اور اسے قتل کر دیا.جب میں
نے یہ واقعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرت و استعجاب
سے فرمایا کہ:
کیا کلمہ پڑھ لینے کے باوجود تم نے اُسے قتل کر دیا
میں نے عرض کیا ! جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.اس پر حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
اُس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب قیامت کے دن کلمہ تمہارے خلاف گواہ
بن کر کھڑا ہو جائے گا
میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بار بار عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم ! وہ تو موت کی وجہ سے ایمان لایا تھا.لیکن ہر بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ:
" کیا تم نے اُس کا دل چیر کر دیکھ لیا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے.“
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جارہے تھے کہ :
اُس کا کلمہ تمہارے خلاف گواہ بن کر کھڑا ہو گا تو تم اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دو گے؟“
حضرت اُسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ میرے دل میں بڑی شدت سے یہ خواہش پیدا ہوئی کہ
کاش میں آج سے پہلے مسلمان ہی نہ ہوا ہوتا کہ مجھ سے یہ فعل سرزد ہوتا.‘ (14)
یہ قرآنی بیان کہ دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں، اگر چہ بہت مختصر ہے لیکن اپنے معانی کے
اعتبار سے اتنا جامع اور اپنے اطلاق کے لحاظ سے اس قدر دور رس اثرات کا حامل ہے کہ اس کا بغور
مطالعہ انسان کو ورطہ حیرت میں ڈال دیتا ہے.اس
کی تشریح یوں کی جاسکتی ہے کہ نہ تو کسی شخص کو دوسروں کے خلاف طاقت استعمال کرنے کی
اجازت ہے اور نہ یہ آیت مظلوم کو جبر کے سامنے سر جھکانے کی اجازت دیتی ہے.اعلیٰ درجے کا
Page 130
118
عدل، احسان اور ایتاء ذى القربى - حصه دوم
ایمان کسی بھی شخص کو کسی جبر کے سامنے جھکنے کی اجازت نہیں دیتا خواہ اسے آزدی ضمیر کی خاطر کتنی بھی
اذیت اور تکلیف کیوں نہ برداشت کرنی پڑے.البتہ ہم اس حقیقت کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے کہ ہر
ایک کے ایمان اور اخلاص کا معیار الگ الگ ہوتا ہے اور پھر سب میں اذیت برداشت کرنے کی
طاقت بھی یکساں نہیں ہوتی.عجیب بات ہے کہ یہی آیت ان کی تائید میں کھڑی ہو جاتی ہے اور
معمولی سی تاکید کی تبدیلی سے مضمون کچھ یوں بنے گا:
کسی سے یہ تقاضا نہیں کیا جاتا کہ وہ اپنی طاقت سے بڑھ کر تکلیف برداشت کرے“
یوں کمزوروں کی بریت کے ساتھ ساتھ یہ یقین دہانی بھی کرائی گئی ہے کہ دباؤ ڈال کر ان سے
جو کچھ کہلوالیا گیا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں کیونکہ مذہب میں جبر کی ہرگز اجازت نہیں.چنانچہ ایک
حرام فعل کا نتیجہ بے حقیقت اور بے اثر ہو جاتا ہے.مندرجہ ذیل آیت میں کمزوروں کیلئے آسانی کے
اسی پیغام کو مزید واضح کر دیا گیا ہے:
مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيْمَانِةٍ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَين
بِالْإِيْمَانٍ وَلَكِنْ مَّنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ
مِّنَ اللهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمُ
(النحل 107:16)
ترجمہ: جو بھی اپنے ایمان لانے کے بعد اللہ کا انکار کرے سوائے اس کے کہ جو
مجبور کر دیا گیا ہو حالانکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو ( وہ بری الذمہ ہے).لیکن وہ لوگ جو شرح صدر سے کفر پر راضی ہو گئے ان پر اللہ کا غضب ہوگا اور
ان کیلئے ایک بڑا عذاب ( مقدر ) ہے.اب ہم ان مومنوں کے معاملے پر غور کرتے ہیں جو باوجو د شدید مخالفت اور اذیت کے حق کا دامن
مضبوطی سے تھامے رکھتے ہیں.وہ نہ صرف اپنے اموال اور دنیوی املاک حق کی خاطر قربان کر دیتے
ہیں بلکہ اپنی جانیں تک قربان کرنے سے دریغ نہیں کرتے.یہی وہ لوگ ہیں جو عدل سے ترقی کر کے
درجہ احسان میں داخل ہوتے ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ایمانوں کو حسین بنالیا ہے.لیکن ایک درجہ احسان سے بھی اعلیٰ ہے اور وہ ہے ایتا عذی القربی.کیا یہ ممکن ہے کہ جو لوگ
اپنے دین کے دفاع میں جنگ کرتے ہیں وہ احسان کرنے والوں سے بھی بڑھ جائیں؟ جہاں تک
ان کی قربانیوں کا تعلق ہے، کیا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق میں ایتا عوذی القربی کے دائرے
میں داخل ہو سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یقیناً وہ ہو سکتے ہیں.وہ اپنا سب کچھ اس وقت تک
Page 131
اسلامی جہاد کے متعلق غلط فهمی
119
نچھاور نہیں کر سکتے جب تک وہ الہی منشا کو اپنا نصب العین نہ بنالیں.ان کیلئے واحد محرک خدا تعالیٰ کی
محبت اور یہ شدید خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ان کی اس محبت کا جواب محبت ہی سے دے.یہ
قربانی اس قربانی سے کہیں بڑھ کر ہے جو حقیقی اور خونی رشتہ دار ایک دوسرے کیلئے پیش کر سکتے ہیں.یہ تو ممکن ہے کہ بعض مائیں شدید اذیت کے وقت اپنی بجائے اپنے بچے کو اس اذیت میں ڈالنے کیلئے
کسی کے حوالے کر دیں لیکن یہ عشاق الہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ چمٹا رہنے کی کوشش میں سب کچھ کر
گزرتے ہیں.تاہم یہ بالکل ممکن ہے کہ ایمان کے لحاظ سے ان کے مدارج میں فرق ہو.کچھ ایسے
بھی ہوتے ہیں جو زندگی قربان کرتے ہیں لیکن اگر ایسی قربانی سے بچنا ممکن ہو تو وہ خوش رہیں
گے.پھر ایسے بھی ہیں جو اپنے دین کی خاطر جان قربان کرنے کی شدید خواہش رکھتے ہیں.چنانچہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے صحابہ نے شدید خطرات کے وقت پیٹھ پھیر کر بھاگ جانے
کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی شہادت کیلئے دعا کی درخواست کی.غزوہ احد میں ہمیں اسی
جوش و جذبہ کی ایک عظیم الشان مثال ملتی ہے.ایک صحابی بار بار میدان جنگ کی انگلی صفوں میں جا کر لڑتے اور ہر بار زندہ سلامت واپس
لوٹ آتے.بالآخر انہوں نے اپنی شہادت کیلئے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی
درخواست کی.ان میں سے بعض ایک بار کی شہادت پر راضی نہ تھے.ان کی دلی تمنا تھی کہ انہیں بار بار زندگی عطا
کی جائے اور وہ کسی بھی ظالم کے آگے سر جھکانے کی بجائے اسی طرح ہر بار حق کی خاطر جان فدا کرتے
چلے جائیں.یقیناً یہی وہ لوگ ہیں جو ایت آ ذی القربی یا اس سے بھی بلند تر مقام پر فائز ہوتے ہیں.بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت اقدس محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اپنے ایک صحابی،
حضرت جابر بن عبد اللہ کو انتہائی مغموم حالت میں دیکھا.حضرت جابڑ کے والد ماجد غزوہ احد میں
شہید ہو گئے تھے.ان کو اس طرح مغموم دیکھ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
کیا میں تمہیں خوشی کی خبر نہ دوں؟“
حضرت جابرؓ نے عرض کیا ”جی ہاں یارسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم “ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
” جب تمہارے والد شہید ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے استفسار فرمایا کہ مانگو
جو مجھ سے مانگنا چاہتے ہو تمہارے والد نے جواباً عرض کیا کہ ”اے میرے
اللہ ! کون سی رحمت اور فضل ایسا ہے جو تو نے مجھ پر نہیں کیا.تاہم ایک خواہش
Page 132
120
عدل، احسان اور ایتاء ذى القربى - حصه دوم
میرے دل میں ابھی باقی ہے کہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے تاکہ میں تیرے
دشمنوں سے پھر مقابلہ کروں اور ایک بار پھر تیری راہ میں مارا جاؤں اور میں
چاہتا ہوں کہ ایسا بار بار، بلکہ سینکڑوں بار ہو.“ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”میں
تمہاری یہ خواہش پوری کر دیتا اگر پہلے سے میرا یہ فیصلہ نہ ہوتا کہ جو کوئی ایک
مرتبہ میرے پاس آجائے اسے میں واپس نہیں لوٹا یا کرتا (15)
قرآن کریم میں دین کی خاطر جان قربان کرنے کے مضمون پر سیر حاصل بحث کی گئی ہے.قرآن کریم ایمان کے ابتدائی مدارج کا ذکر کرتا ہے اور وعدہ فرماتا ہے کہ کمزوروں کے ساتھ انصاف
کا معاملہ کیا جائے گا.اس میں احسان کا بھی ذکر ہے کہ انہیں ضرور ان کے احسان کا بدلہ دیا جائے
گا اور پھر صف اول کے ایسے مومنین کا بھی ذکر ہے جو سچائی سے اس سے بھی بڑھ کر محبت رکھتے ہیں
جتنی ماں اپنے بچے کیلئے رکھتی ہے.وہ اپنی قربانیوں کا کوئی اجر نہیں چاہتے بلکہ انہیں سچائی کی خاطر
قربانیاں پیش کر کے حقیقی طور پر دلی مسرت حاصل ہوتی ہے.
Page 133
عبادت میں عدل، احسان اور ایتاء ذی القربی کا مقام
121
12 عبادت میں عدل، احسان اور ایتا عذی القربیٰ کا مقام
عبادت کے جتنے بھی طریق ہیں ان میں نماز کو مرکزی حیثیت حاصل ہے اور اسے عدل،
احسان اور ایتا و ذی القربی کے تین بنیادی اصولوں کے عین مطابق تشکیل دیا گیا ہے.مندرجہ ذیل
قرآنی آیت میں عدل کا ذکر ملتا ہے:
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّى فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا
دَعَانِ فَلْيَسْتَجِبْوَالِى وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ (البقرہ 2: 187)
ترجمہ: اور جب میرے بندے تجھ سے میرے متعلق سوال کریں تو یقیناً میں
قریب ہوں.میں دعا کرنے والے کی دعا کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے
پکارتا ہے.پس چاہئے کہ وہ بھی میری بات پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں
تا کہ وہ ہدایت پائیں.اس خوشخبری کے ساتھ ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اپنے عبادت گزار بندوں کے بے حد قریب ہے،
قرآن کریم اللہ تعالیٰ اور انسان کے مابین موجود عدل کے تعلق پر بھی روشنی ڈالتا ہے.عبادت محض
یکطرفہ راہ نہیں ہے.ایک عبادت گزار انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کر سکتا جیسے کوئی
غلام، حکم کی بجا آوری کیلئے دست بستہ کھڑا ہو بلکہ نمازی کو چاہئے کہ وہ بھی خدا تعالیٰ کی اطاعت
کرتے ہوئے اس کے احکام پر عمل پیرا ہو.قبولیت دعا کا بنیادی اصول یہی ہے.اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی بنی نوع انسان کو مخاطب کرتے ہوئے یہ خوشخبری دیتا ہے کہ خدا
اور انسان کے مابین مکالمہ و مخاطبہ کوئی دیو مالائی کہانی نہیں ہے بلکہ ایسی زندہ حقیقت ہے کہ جسے پایا
جاسکتا ہے.اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی حق تلفی ہرگز نہیں کرتا لیکن وہ یہ توقع بھی رکھتا ہے کہ وہ بھی اس
کی طرف سے مفوضہ فرائض ادا کریں.خدا تعالیٰ ایسے لوگوں کی دعاؤں کی قبولیت کا وعدہ فرماتا ہے
جو ہمیشہ اس کے احکام کے تابع رہتے ہیں.بنی نوع انسان کی ہدایت اور رہنمائی کیلئے عدل کی یہ تعلیم از حد ضروری ہے.تاہم جس خدا کا
تصور قرآن کریم پیش فرماتا ہے وہ عادل ہی نہیں بلکہ اس سے کہیں بڑھ کر محسن بھی ہے.سو اس کے
بندے اس کی طرف سے، انصاف سے کہیں بڑھ کر امید رکھنے میں حق بجانب ہیں.قرآن کریم کی
مندرجہ ذیل آیت اس بات کی تصدیق کرتی ہے:
Page 134
122
عدل، احسان اور ایتاء ذى القربى - حصه دوم
أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمُ
خُلَفَاءَ الْأَرْضِ ءَ الْهُ مَعَ اللهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ (النمل 63:27)
ترجمہ: یا ( پھر ) وہ کون ہے جو بے قرار کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ اسے
پکارے اور تکلیف دور کر دیتا ہے اور تمہیں زمین کے وارث بناتا ہے.کیا اللہ
کے ساتھ کوئی ( اور ) معبود ہے؟ بہت کم ہے جو تم نصیحت پکڑتے ہو.یہاں المُضْطَر سے ایسے لوگ مراد ہیں جو شدید رنج وغم اور در دوالم میں مبتلا ہوں.بعض
اوقات تو ان کا دکھ اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ جیسے ان کے دل ابھی پھٹ جائیں گے.ایسے مواقع پر
اللہ تعالیٰ محض انصاف سے ہی کام نہیں لیا کرتا بلکہ اپنے بندوں کے ساتھ احسان کا سلوک فرماتا ہے
خواہ ان کے اعمال اس قابل نہ بھی ہوں.ایک مضطر یعنی بے قرار شخص خواہ ہستی باری تعالیٰ کا منکر بھی
ہو بہر حال یہ تو تسلیم کرنا ہی پڑتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے.چنانچہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ عدل
کے لگے بندھے اصولوں سے ہٹ کر معاملہ فرماتا اور اضطراری حالت میں اس پر احسان کرتے
ہوئے اس کی داد رسی فرماتا ہے.اذیت میں مبتلا شخص کی فریاد سنی جاتی ہے اور اس کی سابقہ
بداعمالیوں سے قطع نظر اس کو قبولیت سے بھی نوازا جاتا ہے.ایسی مثالیں دنیا بھر میں ملتی ہیں کہ شدید غم وحزن کے وقت کوئی ملحد بھی اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو
اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے.پس عبادت کے معاملے میں احسان کی یہ علیم ہے.ان مضطر لوگوں میں بے بس، بے گھر کر دیئے جانے والے اور ستم رسیدہ لوگ شامل ہیں.ایسے ہی لوگوں کے بارے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ :
اِتَّقُوا دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ وَإِنْ كَانَ كَافِرًا فَإِنَّهُ لَيْسَ دُونَهَا حِجَابٌ.ترجمہ: مظلوم کی بددعا سے ڈرو اگر چہ وہ کا فر ہی ہو کیونکہ اس کی دعا اور اللہ تعالیٰ
(16)
کے مابین کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا.(
اللہ تعالیٰ اور انسان
کا باہمی تعلق ایتاء ذی القربی کے میدان میں بھی داخل ہو جاتا ہے.جب
کوئی شخص خود کو راہ مولیٰ میں کلیۂ وقف کر دے اور خدا تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں
کسی قسم کی کوئی دوئی
باقی نہ رہے تو وہ ایتا و ذی القربیٰ کے مرتبہ پر فائز ہو جاتا ہے.کیونکہ ایسے لوگ کامل طور پر اپنا آپ
اللہ تعالیٰ کو سونپ دیا کرتے ہیں.پھر بظاہر یہ لگتا ہے کہ ان میں کچھ خدائی صفات جلوہ گر ہوگئی ہیں.
Page 135
عبادت
میں
عدل، احسان اور ایتاء ذی القربیٰ کا مقام
123
یہی تو وہ حظ ہے جو انبیا ء کرام ، اولیاء اللہ اور مقربین الہی اٹھاتے ہیں.چنانچہ
بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ایتا و ذی القربی کے سب سے اعلیٰ مقام پر فائز تھے کیونکہ آپ صلی اللہ
علیہ وسلم نے اپنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے سپر د کر دیا ہوا تھا اور اپنی ذات کی کلیہ نفی کر رکھی تھی.قُلْ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ
(الانعام 6: 163)
ترجمہ: تو کہہ دے کہ میری عبادت اور میری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا
اللہ ہی کیلئے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے.یاد رکھنا چاہئے کہ ہر شخص کا مرتبہ دوسرے سے الگ ہے.اسی لئے خدا تعالیٰ کا سلوک بھی ہر
ایک کے ساتھ الگ الگ ہوگا.جب کسی خاص مرتبہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس سے ہرگز یہ مراد نہیں
ہوتی کہ ایسے لوگ مقام اور درجے کے لحاظ سے برابر ہیں کیونکہ ہر ایک درجہ آگے چھوٹے چھوٹے
کئی درجات پر منقسم ہے.تاہم محض انبیاء کرام ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایتاء ذی القربی کے تعلق کا حظ
نہیں اُٹھاتے بلکہ دیگر لوگ بھی اپنے اپنے مقام اور ظرف کے مطابق اس تعلق سے حصہ پاتے ہیں.چنانچہ نبی اکرم صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
رُبَّ أَشْعَتْ أَغْبَرَ.......لَوْاقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَابَرَّهُ.(17)
یعنی بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو دنیا کی نظر میں نہایت بے کس اور حقیر ہوتے ہیں لیکن
ایسے ہی لوگ ہیں جنہیں خدا کا نہایت قریبی تعلق حاصل ہوتا ہے.یہاں تک کہ اگر وہ یہ کہ دیں کہ
اللہ تعالیٰ ایسا ہی کرے گا تو اللہ تعالیٰ ان کی لاج رکھتے ہوئے ان کا کہا سچ کر دکھایا کرتا ہے.یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے والدین اپنے پیارے بچے سے اور بچہ اپنے والدین سے کچھ توقعات
رکھتا ہے اور اس تعلق کی بنا پر دونوں طرف سے ان توقعات پر پورا اترنے کی کوشش کی جاتی ہے.اسے ہم اصطلاحا دعا تو نہیں کہ سکتے لیکن دعا کے تصور کے ساتھ کچھ مشابہ ہے.بعض اوقات بچہ گھر
والوں کو چھوڑ کر باہر جا کر کھانا کھانا چاہتا ہے لیکن گھر والوں کو اس کی نیت کا علم نہیں کہ باہر گلی میں
انتہائی غریب بچے اس کا انتظار کر رہے ہیں اور وہ یہ سارا کھانا غریب بچوں میں تقسیم کر کے خود کسی
مسجد کے کونے میں جا بیٹھے گا اور اپنی جیب میں پڑے کچھ دانے اور گڑ کھا کر اپنی بھوک مٹالے گا.ایسا معاملہ یقیناً احسان کی حدود پار کر کے ایتاء ذی القربیٰ کے میدان میں جا داخل ہوتا ہے.اس
سے ملتی جلتی قربانیاں اپنے بچوں کے تعلق میں بعض دفعہ ماؤں سے بھی دیکھنے کوملتی ہیں.
Page 136
124
عدل، احسان اور ایتاء ذى القربى - حصه دوم
یہ کوئی خیالی باتیں نہیں ہیں بلکہ بانی جماعت احمدیہ ، حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ
والسلام کے بچپن کی عمر میں تو ایسے واقعات کم و بیش روزانہ ظہور میں آیا کرتے تھے.انبیاءعلیہم السلام کا اپنے پیروکاروں کی شفاعت کرنا بھی درحقیقت دعا ہی کا ایک اعلیٰ درجہ کا پہلو
اور ایتا ء ذی القربیٰ کا اظہار ہے.اس نقطہ نگاہ سے یہ بات بآسانی سمجھ میں آجاتی ہے کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام شفاعت کرنے والوں میں سب سے بلند درجے کا وعدہ کیوں دیا گیا ہے.وہ خدا آج بھی ویسا ہی محسن خدا ہے جس نے حضرت اقدس محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ
صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے دیگر نیک بندوں پر خاص احسانات فرمائے تھے.عام حالات میں
قوانین قدرت اپنا کام جاری رکھتے ہیں لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی کو شفاعت کا اذن عطا فرماتا ہے تو
بعض مخفی قوانین عام قوانین کی جگہ لے لیتے ہیں.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایسا کئی بار
ہوا بلکہ اس زمانے میں بانی جماعت احمدیہ علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملے میں بھی ہم نے بارہا ایسا
ہوتے دیکھا ہے.لیکن بہر حال یہ یاد رکھنا چاہئے کہ یہ کوئی نئی برکت نہیں ہے جو محض
آپ علیہ السلام کے ساتھ ہی خاص ہو بلکہ یہ انہی برکات کا تسلسل ہے جن کا اس زمانے میں ظہور
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ہورہا ہے.وضاحت کی خاطر یہاں صرف ایک مثال پیش کی
جاتی ہے.حضرت منشی ظفر احمد صاحب کپور تھلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد حیات نامی ایک طالب علم، جسے
طاعون ہوگئی تھی ، کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اسے طاعون ہو گئی.حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ
والسلام نے معائنہ کیلئے اپنے پیارے صحابی حضرت حکیم مولوی نور الدین رضی اللہ عنہ کو وہاں بھیجا.مریض کی حالت دیکھتے ہی انہوں نے طاعون کی ساری علامات اس میں پائیں.محمد حیات شدید بخار
میں تپ رہا تھا، جسم پر چھ گلٹیاں بھی صاف دکھائی دے رہی تھیں اور پیشاب کے ساتھ خون بھی آنا
شروع ہو چکا تھا.آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حالات عرض
کیسے نیز یہ اشارہ بھی کر دیا کہ مریض کی حالت سے لگتا ہے کہ وہ زندگی کی نسبت موت سے زیادہ قریب
ہے.حضرت حکیم مولوی نورالدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ نہایت محتاط الفاظ استعمال فرمایا کرتے تھے
جبکہ دنیا میں اطباء اور حکماء بلاتر دو اپنی رائے کا اظہار کر دیا کرتے ہیں اور بالخصوص اس قسم کے کیس میں
تو ان کی یہی رائے ہوتی کہ مریض کی موت یقینی ہے.لیکن چونکہ حضرت مولوی صاحب رضی اللہ عنہ
بخوبی جانتے تھے کہ موت کے بارے میں جب تک امرالہی نہ آجائے تب تک کسی کی موت کے
Page 137
عبادت
میں
عدل، احسان اور ایتاء ذی القربی کا مقام
125
بارے میں قطعی رائے قائم کرنا درست نہیں ہوتا.اس لئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف اس
امکان کا اظہار فرمایا کہ بچ جانے کی نسبت موت کا شکار ہونے کے امکانات زیادہ ہیں.حضرت منشی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ
والسلام سے درخواست کی کہ محمد حیات کیلئے دعا کریں جس پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام
فور دعا کیلئے تیار ہو گئے.حضرت منشی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھبراہٹ سے عرض کیا کہ
حضور! دعا کا وقت تو نکل چکا ہے اب تو صرف شفاعت ہی کام آسکتی ہے نوجوان کی حالت
بہت ہی دگر گوں تھی.حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اندر تشریف لے گئے اور پوری توجہ
سے دعا میں مشغول ہو گئے.صبح دو بجے کے قریب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے چھت پر تشریف لا کر محمد حیات
کی صحت کے بارہ میں استفسار فرمایا.ہم میں سے کسی نے کہا کہ ”شاید اب تک تو وہ فوت بھی ہو چکا
ہو.آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جاؤ اور اس کا پتہ کرو.جب ہم اس کا پتہ کرنے پہنچے تو
اسے باغیچے میں چہل قدمی اور تلاوت قرآن کریم کرتے پایا.اس نے کہا کہ ڈرنے کی اب کوئی
ضرورت نہیں ، میرے قریب آئے کیونکہ گلٹیاں بھی سرے سے غائب ہو چکی ہیں اور بخار بھی بالکل
جاتا رہا ہے اور اب میں مکمل طور پر صحت مند ہوں.ہم نے واپس حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ
والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر محمد حیات کے متعلق بتایا کہ وہ بالکل تندرست ہو چکا ہے.جس پر
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ:
پھر تم اسے اپنے ساتھ کیوں نہیں لے کر آئے.“
قبل از میں محمد حیات کے والد صاحب
کو ٹیلی گرام کے ذریعہ یہ اطلاع بھجوائی جا چکی تھی کہ ان کے
بیٹے کا بچنا اب محال ہے لیکن اب یہ سمجھا گیا کہ اس عظیم الشان معجزہ کے بارہ میں انہیں بتایا جانا اشد
ضروری ہے تا کہ ان کو بھی ذہنی اطمینان اور سکون حاصل ہو.چنانچہ ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ
والسلام سے اجازت لے کر بٹالہ کیلئے روانہ ہو گئے تاکہ وہاں سے ایک اور ٹیلی گرام دیا جا سکے.بٹالہ
قادیان کے مغرب میں بارہ میل کی مسافت پر ایک قصبہ ہے جہاں ٹیلی گرام وغیرہ کی سہولت میسر تھی
لیکن ہماری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی کہ جب قادیان سے صرف دو میل دور نہر کے کنارے کنارے ہم
نے دیکھا کہ ایک تانگے میں سوار حیات صاحب ( محمد حیات خان کے والد.مترجم) قادیان کی طرف
چلے آرہے ہیں.انہوں نے ہم سے دریافت کیا کہ ”حیات خان کیسا ہے؟“ ہم نے انہیں اس معجزے
کے بارے میں بتایا.وہ یہ خوشخبری سن کر بے ہوش ہو گئے.جب انہیں ہوش آیا تو وضو کیا اور شکرانے
Page 138
126
عدل، احسان اور ایتاء ذی القربى - حصه دوم
کے نوافل ادا کرنے لگے.پھر ہم لوگ واپس گھروں کو لوٹ آئے.(18)
فلسفه دعا
اب ہم آداب دعا کی طرف لوٹتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ دعا کیسے مانگنی چاہئے؟ فلسفہ دعا کا
ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں صاف طور پر فرماتا ہے کہ جولوگ صرف دنیوی نعماء طلب
کرتے ہیں انہیں صرف وہی عطا کی جاتی ہیں لیکن خدا کے بندے ان ادنی ادنیٰ اشیاء پر راضی نہیں
ہوتے.چنانچہ قرآن کریم سچے مومنوں
کو یہ دعا مانگنے کی تلقین فرماتا ہے کہ:
رَبَّنَا اتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ
( البقرة 202:2)
ترجمہ: اے ہمارے رب! ہمیں دنیا میں بھی حسنہ عطا کر اور آخرت میں بھی
حسنہ عطا کر اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا.مختلف احادیث کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک
صحابی کو یہ دعا مانگنے کی ہدایت فرمائی تھی.بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی بیمار پڑ گئے.وہ
انتہائی کمزور لاغر اور دبلے پتلے ہو گئے.ان کی حالت کا ذکر کرتے ہوئے ایک اور صحابی بیان کرتے
ہیں کہ گویا کسی پرندہ کے پر نوچ لئے گئے ہوں.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کیلئے
تشریف لے گئے.آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ان کی نفسیات سے اچھی طرح واقف تھے اس لئے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محض ایک ہی بات ان سے پوچھی کہ :
" کیا تم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہو کہ وہ تمہاے نیک اعمال کی جزاء صرف
آخرت میں دے اور اس زندگی میں نہیں ؟
صحابی نے عرض کیا جی ہاں ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ، کچھ ایسا ہی ہے کہ میں
اللہ تعالیٰ سے یہ التجا کرتا ہوں کہ وہ میرے تمام گناہوں کی سزا مجھے اسی زندگی میں دے دے
لیکن آخرت میں آگ کے عذاب سے بچالے.اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
" سبحان
اللہ ! تم اس کے غضب کو برداشت کرنے کی طاقت ہی کہاں رکھتے
ہو؟ تمہیں تو یہ دعا کرنی چاہئے تھی کہ اللہ اس دنیا کی حسنات بھی عطا فرمائے
اور آخرت کے عذاب سے بھی بچائے.“
چنانچہ بیان کیا جاتا ہے کہ پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کیلئے دعا کی تو ان کی حالت
بہتر ہونا شروع ہوئی یوں وہ موت کے چنگل سے رہا ہوئے.(
(19)
Page 139
عبادت
میں
عدل، احسان اور ایتاء ذی القربیٰ کا مقام
127
یہ دلچسپ واقعہ عدل کے ساتھ ساتھ احسان اور ایتاً و ذی القربیٰ کا بھی احاطہ کئے ہوئے ہے.اگر ایک شخص صرف انصاف کا طالب ہے تو اس کے ساتھ محض انصاف ہی برتا جائے گا.لیکن
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت فرمائی ہے کہ ہم ہمیشہ انصاف کی بجائے رحم مانگیں.جہاں تک مذکورہ بالا واقعہ کا تعلق ہے تو اس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعانے مریض کو موت
کے منہ سے چھڑالیا.یہ در حقیقت ایتا عذی القربی کا اظہار ہے.وگرنہ اس قدر خطر ناک بیماری سے
بچ نکلنے کا بظا ہر کوئی امکان دکھائی نہیں دیتا تھا.دعا کے مضمون کے ضمن میں اب ہم جائزہ لیتے ہیں کہ عدل ، احسان اور ایتاً ذی القربی دیگر
طریق ہائے عبادت میں کس طرح اپنا کردار ادا کرتے ہیں.بانی جماعت احمد یہ حضرت مرزا غلام احمد
بالصلوة والسلام نے اس ضمن میں ان تینوں موضوعات پر الگ الگ روشنی ڈالی ہے.ذیل میں آپ
علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریرات میں سے کچھ اقتباسات درج کئے جاتے ہیں.آپ فرماتے ہیں:
" خدا تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے در حقیقت تین قسم پر منقسم ہیں.اول وہ
لوگ جو بباعث محجوبیت اور رؤیت اسباب کے احسانِ الہی کا اچھی طرح
ملاحظہ نہیں کرتے اور نہ وہ جوش ان میں پیدا ہوتا ہے جو احسان کی عظمتوں پر نظر
ڈال کر پیدا ہوا کرتا ہے اور نہ وہ محبت ان میں حرکت کرتی ہے جو محسن کی
عنایات عظیمہ کا تصور کر کے جنبش میں آیا کرتی ہے.(20)
انسان اپنے روزمرہ معاملات میں ہر وقت احسان الہی کا دست نگر ہے.دن ہو یا رات ،
سوتے اور جاگتے گویا ہر ایک حرکت میں وہ برکات خداوندی کا مهبط ہے.بعض لوگ اپنی زندگی
غفلت میں ہی گزار دیتے ہیں اور انہیں یہ عرفان ہی نہیں ہو پا تا کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنے فضلوں کی
بارش مسلسل برساتا چلا جا رہا ہے.حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام مزید فرماتے ہیں:
چونکہ خدا تعالیٰ انسان کو اس کے وسعت فہم سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا اس
لئے ان سے جب تک کہ وہ اس حالت میں ہیں یہی چاہتا ہے کہ اس کے حقوق
کا شکر ادا کریں اور آیت إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدُلِ میں عدل سے مراد یہی
(21)..اطاعت برعایت عدل ہے.“
وہ لوگ جو خوف کھاتے ہیں اپنی نمازوں کے متعلق جن میں ان
کو سرور نہیں مل رہا ہوتا.جن میں
وہ خدا تعالیٰ کے حضور حضوری کے جذبات نہیں پاتے اور بڑے فکر کے بعض لوگوں کے خط آئے ہیں
Page 140
128
عدل، احسان اور ایتاء ذى القربى - حصه دوم
ان کو کم از کم اتنی خوشخبری تو ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ انکے حال کے مطابق معاملہ کرے گا
اور یہاں عدل بھی اللہ کا احسان ہے وہ جانتا ہے آپ کی کیفیات کو آپکی کمزوریوں کو.خدا تعالیٰ یہاں
عدل کا سلوک فرمائے گا.بہت اچھا تو نے اپنی طاقت کے مطابق تو عبادت شروع کر دی میں اسی کو
قبول کر لیتا ہوں لیکن اسپر کھڑے رہنا مومن کا کام نہیں کیونکہ ترقیات کے لامتناہی آگے دروازے
کھلے ہیں اور یہی عبادت پھر احسان میں داخل ہو جاتی ہے.چنانچہ حضرت مسیح موعود اس کا ذکر کرتے
ہوئے فرماتے ہیں:
اس سے بڑھ کر ایک اور مرتبہ انسان کی معرفت کا ہے اور وہ یہ ہے کہ جیسا کہ
ہم ابھی بیان کر چکے ہیں انسان کی نظر رویت اسباب سے بالکل پاک اور منزہ
ہو کر خدا تعالیٰ کے فضل اور احسان کے ہاتھ کو دیکھ لیتی ہے اور اس مرتبہ پر
انسان اسباب کے حجابوں سے بالکل باہر آ جاتا ہے اور یہ مقولہ کہ مثلاً میری اپنی
ہی آبپاشی سے میری کھیتی ہوئی یا میرے اپنے ہی بازو سے یہ کامیابی مجھے ہوئی یا
زید کی مہربانی سے فلاں مطلب میرا پورا ہوا اور بکر کی خبر گیری سے میں تباہی
سے بچ گیا.یہ تمام باتیں بیچ ہیں اور باطل معلوم ہونے لگتی ہیں اور ایک ہی ہستی
اور ایک ہی قدرت اور ایک ہی محسن اور ایک ہی ہاتھ نظر آتا ہے.تب انسان
ایک صاف نظر سے جس کے ساتھ ایک ذرہ شرک فی الاسباب کی گرد و غبار نہیں
خدا تعالیٰ کے احسانوں کو دیکھتا ہے اور یہ رویت اس قسم کی صاف اور یقینی ہوتی
ہے کہ وہ ایسے محسن کی عبادت کرنے کے وقت اس کو غائب نہیں سمجھتا بلکہ یقیناً
اس کو حاضر خیال کر کے اس کی عبادت کرتا ہے اور اس عبادت کا نام
قرآن شریف میں احسان ہے اور صحیح بخاری اور مسلم میں خود آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے احسان کے یہی معنی بیان فرمائے ہیں، (22)
اس طرح انسان مقام عدل سے ترقی کر کے مقام احسان
کو پالیتا ہے.جب ہم ذکر الہی میں
اس قدر کھوئے جائیں تو اللہ تعالیٰ کا احسان اس کی محبت کے ساتھ ساتھ ہمارے رگ و ریشے میں
سرایت کر جاتا ہے.تب اس کے احسان کی قدر دانی محض ایک دلچسپ ذہنی عمل نہیں ہوتا بلکہ اس کے
جذبات کا طبعی جزو بن جاتی ہے.نتیجہ ایسا انسان ایک سچی تڑپ کے ساتھ خدا تعالیٰ سے محبت کرنے
(22)،،
Page 141
عبادت میں عدل، احسان اور ایتاء ذی القربی کا مقام
129
لگتا ہے.پس جو شخص اس طریق پر عبادت بجالاتا ہے وہ دیکھے گا کہ اب اس کیلئے اپنی پہلی غفلت کی
حالت میں دوبارہ لوٹ جانا ناممکن ہو چکا ہے اور وہ قطعاً نہیں چاہے گا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وصل کی
اس کیفیت میں کسی قسم کا کوئی تعطل واقع ہو.حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اسی مرکزی خیال کو
آگے بڑھاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ :
اس درجہ کے بعد ایک اور درجہ ہے جس کا نام ایتاء ذی القربی ہے اور
تفصیل اس کی یہ ہے کہ جب انسان ایک مدت تک احسانات الہی کو بلا شرکتِ
اسباب دیکھتار ہے اور اس کو حاضر اور بلا واسطہ حسن سمجھ کر اس کی عبادت کرتا
رہے تو اس تصور اور تخیل کا آخری نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک ذاتی محبت اس کو جناب
الہی کی نسبت پیدا ہو جائے گی کیونکہ متواتر احسانات کا دائمی ملاحظہ بالضرورت
شخص ممنون کے دل میں یہ اثر پیدا کرتا ہے کہ وہ رفتہ رفتہ اس شخص کی ذاتی محبت
سے بھر جاتا ہے جس کے غیر محدود احسانات اس پر محیط ہو گئے.پس اس
صورت میں وہ صرف احسانات کے تصور سے اس کی عبادت نہیں کرتا بلکہ اس
کی ذاتی محبت اس کے دل میں بیٹھ جاتی ہے جیسا کہ بچہ کو ایک ذاتی محبت اپنی
ماں سے ہوتی ہے.پس اس مرتبہ پر وہ عبادت کے وقت صرف خدا تعالیٰ کو
دیکھتا ہی نہیں بلکہ دیکھ کر بچے عشاق کی طرح لذت بھی اٹھاتا ہے اور تمام
اغراض نفسانی معدوم ہو کر ذاتی محبت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے اور یہ وہ
مرتبہ ہے جس کو خدا تعالیٰ نے لفظ ابْتَائِ ذِي الْقُرْبی سے تعبیر کیا ہے
اور اسی کی طرف خدا تعالیٰ نے اس آیت میں اشارہ کیا ہے ، فَاذْكُرُوا اللهَ
كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا ،، * (23)
ترجمہ: اللہ کا ذکر کرو جس طرح تم اپنے آباء کا ذکر کرتے ہو بلکہ اس سے بھی بہت
زیادہ ذکر.کیسا عمدہ اسلوب تحریر ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے محبت الہی کے لطیف
ترین پہلوکو بھی اندرونی تفاصیل کے ساتھ بیان فرما دیا ہے.آگے چل کر مزید فرماتے ہیں:
Page 142
130
عدل، احسان اور ایتاء ذى القربى - حصه دوم
یہ وہ مرتبہ ہے جس میں تمام اغراض نفسانی جل جاتے ہیں اور دل ایسا محبت
سے بھر جاتا ہے جیسا کہ ایک شیشہ عطر سے بھرا ہوا ہوتا ہے اسی مرتبہ کی طرف
اشارہ اس آیت میں ہے کہ ، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِى نَفْسَهُ ابْتِغَاء
*
مَرْضَاتِ اللهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ یعنی بعض مومن لوگوں میں سے
وہ بھی ہیں کہ اپنی جانیں رضائے الہی کے عوض بیچ دیتے ہیں اور خدا ایسوں ہی
پر مہربان ہے.66
(24)
بالفاظ دیگر ایسے لوگ کسی مخفی محرک کے تابع اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کر رہے ہوتے.وہ کسی
صلے اور اجر کے طالب نہیں ہوتے.یعنی انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ ان کو اچھے اعمال کا
بدلہ ملتا ہے یا نہیں.اگر کوئی شخص محض اللہ کوئی نیکی بجالاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس پر کرم نوازی فرماتا
ہے.لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جو بات بیان فرما ر ہے ہیں وہ محنت اور صلے کے اس
فلسفے سے بہت بالا ہے.اس اعلیٰ مقام پر فائز لوگ محض جنت کمانے کیلئے اچھے اعمال بجا نہیں لاتے
بلکہ وہ تو صرف اور صرف رضائے باری تعالیٰ کے حصول کی خاطر ایسا کرتے ہیں کیونکہ خدا تعالیٰ کی
رضا انہیں دل و جان سے بھی پیاری ہوتی ہے اور اسے خوش کرنا ہی دراصل ان کی جنت اور ان کی
زندگیوں کا واحد مقصد ٹھہرتا ہے.الغرض اسلامی نظام عبادت حیرت
انگیز طور پر بےحد متوازن اور مکمل ہے جس کی تمام باریک
تفاصیل پر عدل، احسان اور ایتا و ذی القربی کی چھاپ دکھائی دیتی ہے.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
ایک انسان تھے اور کسی انسان کیلئے ممکن نہیں تھا کہ وہ قرآن کریم جیسا بے نظیر معجزہ لائے.یہ لازماً
ایک علیم وخبیر اور قادر مطلق خدا کا ہی کام تھا.ہم عبادت کی روح پر بحث کر چکے ہیں.اب ہم کچھ ایسے نظر آنے والے ستونوں کی بات
کرتے ہیں جن کے سہارے عبادت قائم ہوتی ہے اور اس امر کا جائزہ لیتے ہیں کہ کیا یہاں بھی
عدل، احسان اور ایتا عذی القربی کوئی اہم کردار ادا کر رہے ہیں؟
عدل نے اسلامی عبادات کے تمام بنیادی پہلوؤں کا احاطہ کر رکھا ہے.نمازیں مساجد اور
گھروں میں باجماعت اور اکیلے اکیلے ادا کی جاتی ہیں.اگر اسلام نے صرف باجماعت نماز کا ہی حکم
دیا ہوتا تو لوگوں کی اکثریت آہستہ آہستہ نماز کی ادائیگی چھوڑ بیٹھتی.اگر اسلام نے باجماعت نماز کا
Page 143
عبادت
میں
عدل، احسان اور ایتاء ذی القربیٰ کا مقام
131
کوئی متبادل مقرر نہ فرمایا ہوتا تو ہوسکتا تھا کہ چرچ کا رخ نہ کرنے والے عیسائیوں کی طرح مسلمانوں
کی روزمرہ زندگی سے بھی نمازیں بکلی غائب ہو چکی ہوتیں.عبادت میں عدل کا ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ انفرادی اور اجتماعی نمازوں کو یکجا کر دیا گیا ہے.انفرادی
نمازیں تقریباً تمام با جماعت فرض نمازوں کے ساتھ ادا کی جاتی ہیں.ایک اور قابل ذکر حقیقت یہ بھی ہے کہ نماز با جماعت مردوں کی طرح عورتوں پر بھی فرض کر دی
جاتی تو ان پر ایک نا قابل برداشت بوجھ پڑ جا تا کیونکہ وہ بالعموم گھر کی نگرانی اور بچوں کی دیکھ بھال کی
ذمہ دار ہوتی ہیں.اس صورت میں ایک چھوٹا بچہ جسے مسلسل نگہداشت کی ضرورت ہوتی ہے اس کی
ماں
کو بھی مسجد جانا پڑتا جو کہ ماں اور بچہ دونوں کے ساتھ ظلم ہے اور عدل کے تقاضوں کے برخلاف.یہ اسلامی تعلیمات میں پائے جانے والے توازن کی ایک نہایت عمدہ مثال ہے.بعض دیگر حالات
مثلاً حیض یا خون نفاس کے ایام میں خواتین کو انفرادی اور اجتماعی تمام عبادات سے مکمل رخصت دے
دی گئی ہے.عبادت کی ایک اور خصوصیت اسے بآواز بلند یا خاموشی سے ادا کرنے کا اختیار بھی ہے.انسانی
مزاج صبح سے شام تک اور پھر رات کے بعد صبح تک ہونے والی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ بدلتا رہتا
ہے.صبح اور شام نیز رات کی گھڑیاں بہت سے لوگوں میں گنگنانے کا میلان پیدا کرتی ہیں.دن کے
درمیانی حصہ یعنی زوالِ آفتاب سے لے کر سہ پہر تک پرندے بھی چہچہانا بند کر دیتے ہیں.یہ وقت
سکوت اور قیلولہ کا ہوتا ہے.یہی وجہ ہے کہ روزانہ پانچ میں سے تین نمازوں میں قِرَاءَتْ بِالْجَهْرِ
رکھی گئی ہے اور باقی دو نمازیں خاموشی سے ادا کی جاتی ہیں.اسی طرح ان تینوں نمازوں کے کچھ حصے
میں بلند آواز کی اجازت ہے جبکہ باقی حصے خاموشی کے متقاضی ہیں.مزاجوں کی تبدیلی کا تعلق صرف
اوقات کی تبدیلی سے ہی نہیں بلکہ مختلف لوگوں کے مزاج بھی مختلف ہوتے ہیں.چنانچہ سب کے
مناسب حال احکام ہیں.نماز تہجد کے متعلق حکم بالکل منفرد انداز رکھتا ہے.اس نماز کیلئے یہ لازمی قرار نہیں دیا گیا کہ
صرف دل میں پڑھی جائے یا ضرور بلند آواز سے قرآت کی جائے بلکہ دونوں کے مابین رستہ اختیار کیا
جاسکتا ہے جیسا کہ فرمایا:
وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا
Page 144
132
عدل، احسان اور ایتاء ذى القربى - حصه دوم
ترجمہ: اور اپنی نماز نہ بہت اونچی آواز میں پڑھ اور نہ اسے بہت دھیما کر اوران
کے درمیان کی راہ اختیار کر.مندرجہ ذیل حدیث اس آیت کی تشریح کرتی ہے:
حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بالکل خاموشی کے ساتھ تہجد ادا کیا کرتے
تھے.یہاں تک کہ آپ کے ساتھ کھڑا آدمی بھی آپ کی ہلکی سی آواز بھی نہ سن
سکتا تھا.اس کے برعکس حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بلند آواز سے قراءت کیا
کرتے تھے.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت ابوبکر
رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ ” آپ دل ہی دل میں نماز کیوں پڑھتے ہیں؟“
حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جواب میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم ! میں جس تک اپنی مناجات پہنچانا چاہتا ہوں اس تک تو پہنچ جاتی ہیں لہذا
میرے لئے یہی کافی ہے.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ” بالکل
خاموشی سے دل ہی دل میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے.دھیمی آواز میں پڑھنا
چاہئے.حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مزاج حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مختلف
تھا.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے استفسار پر کہ وہ تہجد میں بآواز بلند تلاوت
کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ ”میں تلاوت قرآن کریم کے ذریعے
شیطان کو دور بھگاتا ہوں.اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
شیطان کو اس طریق پر سزا دینے کی ضرورت نہیں ، دھیمی آواز میں تلاوت کرنی
چاہئے.کیونکہ تہجد میں بآواز بلند قرآت کرنے سے ارد گرد موجود لوگوں کی
(25)،،
عبادت میں خلل واقع ہوسکتا ہے
ایک اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بآواز بلند نماز تہجد ادا
کرنے سے بعض غیر مسلوں کی نیند میں خلل واقع ہوا جس پر وہ ناراض ہوئے اور آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا کہ
دوسروں کا خاص خیال رکھا جائے اور ان کی نیند میں مخل نہ ہوا جائے.تاہم آواز میں دھیمی رکھنے کا حکم
Page 145
عبادت
میں
عدل، احسان اور ایتاء ذی القربیٰ کا مقام
133
محض ساتھ والے ہمسایوں کی خاطر نہیں بلکہ مسلمانوں کے اپنے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے موجود
ہو سکتے ہیں جن کے آرام میں اس وقت ہرگز خلل نہیں ڈالنا چاہئے.بعض ایسے بیمار لوگ یا خواتین
ہوسکتی ہیں جن کا تہجد کیلئے جاگنا ضروری نہیں.نماز تہجد ادا کرنے والے کو چاہئے کہ ان سب کی خاطر
اپنی آواز کو دھیما رکھے.مندرجہ بالا آیت واضح طور پر ہم سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ ہم ان دونوں
انتہاؤں کے مابین ایک متوازن راہ اختیار کریں تا کہ تہجد نہ پڑھنے والے تہجد پڑھنے والوں کی وجہ
سے تنگ نہ ہوں.ایک وقت تھا جب مسلم ممالک میں نماز فجر کی اذان لاؤڈ سپیکر پر نہیں دی جاتی تھی.چنانچہ دھیمی
آواز صرف ان لوگوں کو ہی بیدار کیا کرتی تھی جو واقعتہ اسے سننا چاہتے اور علی اصبح اٹھنے کی نیت رکھتے
تھے.اس طرح اذان کی آواز مسجد کے
اردگرد ہمسایوں تک محدود رہتی تھی لیکن اب صورت حال یکسر
مختلف ہے.اب تو ملاؤں کی انا کی تسکین نہیں ہوتی جب تک اذان انتہائی بلند آواز میں اور طاقتور ترین
لاؤڈ سپیکر کے ذریعے نہ دی جائے.اگر بات ایک سپیکر تک محد و در رہتی تو اس قدر نا قابل برداشت نہ ہوتی
جتنی اب ہو چکی ہے.اب تو لوگ بے شمار اذا نہیں سنے پر مجبور ہیں.ایک اذان ختم ہوتی ہے تو دوسری
شروع ہو جاتی ہے.یہ سب اذانیں مختلف آوازوں اور مختلف اوقات میں کہی جاتی ہیں اور ان انتہائی
طاقتور لاؤڈ سپیکروں کی بدولت دُور دُور کے رہنے والے بھی ان اذانوں سے مستفید ہوتے ہیں.بعض مولوی حضرات پو پھٹنے سے قبل ہی اذان شروع کر دیتے ہیں اور بعض کافی دیر بعد اذان کہنا شروع
کرتے ہیں.نتیجہ بے سری آوازوں کا تقریباً نہ ختم ہونے والا سلسلہ چل نکلتا ہے.پھر اسی پر بس نہیں بلکہ بعض تو لہک لہک کر اذانیں کہ رہے ہوتے ہیں اور بعض محض بھڑی
آوازوں میں لڑا رہے ہوتے ہیں.بعض ملاؤں نے تو ایسے طریق اختیار کر لئے ہیں جن کا
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نام و نشان تک نہیں ملتا.بہت سے ملاں نماز فجر کے
وقت سے بہت پہلے حمدیں اور نعتیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں پھر کہیں جا کر اذان کی باری آتی ہے.چنانچہ نماز تہجد سے لے کر صبح صادق کے طلوع ہونے تک بشمول غیر مسلموں کے تمام لوگوں کی نیند اور
سکون اسی طرح بر باد کیا جاتا ہے.بعض مولوی یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ان کی آواز بہت سریلی اور سحرانگیز ہے.وہ اسی یقین کے ساتھ خود
ستائشی میں مبتلا ہوتے ہیں گویا سارا شہر ان کی سریلی آواز کا منتظر ہے.حالانکہ انہیں یہ محسوس نہیں ہورہا ہوتا
کہ وہ تو محض دہشت پھیلا رہے ہیں.افسوس! کہ وہ اس آیت قرآنی پر نظر ڈالنا بھی گوارا نہیں کرتے:
Page 146
134
عدل، احسان اور ایتاء ذى القربى - حصه دوم
وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ اِنَّ اَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ
(لقمان 20:31)
ترجمہ: اور اپنی آواز کو دھیما رکھ.یقیناً سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے.بیان کیا جاتا ہے کہ ممتاز مسلم صوفی بزرگ، حضرت شیخ سعدی شیرازی ایک مرتبہ ایک ایسے
آدمی کے پاس سے گزرے جو بآواز بلند تلاوت قرآن کریم میں مصروف تھا.بدقسمتی سے اس کی
آواز نہایت بھڑی تھی.آپ نے اُسے نرم اور دھیمے لہجہ میں تلاوت کی نصیحت فرمائی.اس پر وہ بولا :
میں تو محض خدا تعالیٰ کی خاطر بآواز بلند تلاوت کر رہا ہوں.تم دخل اندازی کرنے والے کون
ہوتے ہو؟‘ شیخ سعدی نے جواباً فرمایا: ”خدارا! اس قد را ونچی آواز میں تلاوت نہ کر دور نہ لوگ اللہ
اور اس کے اس پاکیزہ کلام سے ہی برگشتہ ہو جائیں گے.“
اسلام ایک عالمگیر مذہب ہونے کا دعویدار ہے چنانچہ اس کے طریق عبادت میں بھی اس کے
الہامی سرچشمہ کی آفاقیت نظر آنی چاہئے.یہ عدل کے تقاضے کے منافی ہوگا کہ لوگوں پر کوئی ایسا نیا
طریق عبادت عائد کر دیا جائے جو ان کے سابقہ روایتی طریق کو بالکل رد کر دے یہاں تک کہ انہیں
اسلام کے تجویز کردہ طریق اور اپنے طریق میں کوئی مشابہت ہی دکھائی نہ دے.بعض مذاہب میں لوگ دوزانو بیٹھ کر ذکر الہی کرتے ہیں اور بعض میں رکوع کرنے کو ترجیح
دیتے ہیں.مختلف لوگ مختلف طریق پسند کرتے ہیں.بعض خدا کے حضور بازو کھلے چھوڑ کر اور بعض
باز و تہہ کر کے کھڑے ہوتے ہیں.بعض مذاہب میں جھک جانا ہی عبادت کے مرکزی نقطہ کی حیثیت
رکھتا ہے جبکہ بعض دیگر مذاہب میں پیشانی کو زمین پر رکھ دینا عقیدت کے اظہار کا نقطۂ معراج سمجھا
جاتا ہے.اسلام نے بڑی جامعیت کے ساتھ ان سب طریق ہائے عبادت کو اس طرح یکجا کر دیا
ہے کہ جزوی طور پر ہر مذہب کی نمائندگی ہو جاتی ہے.اسلامی احکام نماز میں معاشرے کے ہر طبقے اور ہر انسانی حالت کا خیال رکھا گیا ہے.مسجد
کے قرب و جوار میں آباد تندرست مردوں کیلئے ضروری ہے کہ وہ دن میں پانچ مرتبہ نماز باجماعت کی
ادائیگی کیلئے مسجد جائیں اور نمازوں کے اوقات اس طرح مقرر کئے گئے ہیں کہ عموماً وہ کسی کے
روزمرہ پروگرام میں مخل نہیں ہوتے.مثلاً نماز ظہر دو پہر کے کھانے کے وقفہ میں بآسانی ادا کی جاسکتی
Page 147
عبادت میں عدل، احسان اور ایتاء ذی القربی کا مقام
135
ہے اور اگر مسجد قریب ہو تو وہاں جا کر وقت مقررہ پر باجماعت نماز ادا کرنے میں کوئی مشکل در پیش
نہیں ہونی چاہئے.باقی چار نمازیں ایسے اوقات میں ادا کی جاتی ہیں کہ جب لوگ عموماً اپنے ضروری
دنیوی کاموں سے فارغ ہو چکے ہوتے ہیں.تاہم بعض صورتوں میں ایک شخص کے پیشہ وارانہ
فرائض اس بات میں روک بن جاتے ہیں کہ وہ شخص تمام نمازیں مسجد میں جا کر ادا کرے.مثلاً
کسان طلوع فجر سے بہت پہلے اپنا کام شروع کر چکے ہوتے ہیں اور چرواہے اپنے ریوڑ دور دراز کی
چرا گاہوں کی طرف ہانک لے جاتے ہیں.ایسے لوگوں کیلئے یہ امر بہر حال مشکل اور دقت طلب ہے
کہ اپنا کام چھوڑ کر قریبی مساجد کی تلاش میں نکل کھڑے ہوں.اس لئے انہیں رخصت دی گئی ہے
کہ جہاں نماز کا وقت ہو جائے وہیں ادا کر لیں.یہ رخصت عدل کے تقاضوں کے مطابق نہیں بلکہ یہ
ایک قدم آگے بڑھ کر احسان کے دائرہ میں داخل ہو جاتی ہے.حدیث میں آتا ہے کہ:
ایک مرتبہ ایک گڈریے نے سنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انفرادی نماز
کی نسبت نماز باجماعت کی فضیلت پر بہت زور دیا ہے تو اس نے نہایت
عاجزی سے عرض کیا کہ اس کا زیادہ تر وقت تو آبادی سے دور صحرا میں گزرتا ہے
وہ کس طرح نماز باجماعت ادا کر سکتا ہے؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ ایسی صورت میں کہ جب صحرا میں نماز کا وقت ہو جائے تو اذان کہو.اگر
تو قرب و جوار میں کوئی مومن موجود ہوا تو تم سے آن ملے گا یوں تم نماز
باجماعت ادا کر سکو گے بصورت دیگر جب تم نماز کیلئے کھڑے ہو گے تو فرشتے
آسمان سے اتر کر تمہارے ساتھ نماز میں شامل ہو جائیں گے.اس حدیث مبارکہ سے کئی نتائج اخذ کئے جاسکتے ہیں:
1: اگر کسی کی راہ میں اس کے پیشہ وارانہ فرائض حائل ہوں تو اسے نمازوں کیلئے مسجد آنے سے
رخصت ہے.2: اگر وہ اپنی سہولت والی جگہوں پر نماز باجماعت کا بآسانی انتظام کر سکے تو باقاعدہ مسجد میں
جا کر نماز ادا نہ کر سکنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے حضور اس کی نماز با جماعت ہی شمار ہوگی.3: اگر اس کی خواہش کے باوجود کوئی دوسرا شخص نماز با جماعت کیلئے نہ ملے تو بھی اللہ تعالیٰ اس
Page 148
136
کی نماز ، باجماعت ہی قبول فرمائے گا.عدل، احسان اور ایتاء ذى القربى - حصه دوم
مندرجہ بالا حدیث میں بیک وقت عدل، احسان اور ایتا و ذی القربی کے تینوں درجات شامل
ہیں.عدل اس طرح کہ کسی کو بھی اس کی طاقت سے بڑھ کر مکلف نہیں ٹھہرایا گیا.احسان اس طرح
کہ نماز کیلئے کسی کو میسر آنے والی زمین کا ہر ٹکڑا اللہ تعالیٰ نے مسجد قرار دے دیا ہے اور فرشتوں کو اس
کے ساتھ شامل ہونے کا حکم دے کر ایتا ء ذی القربی والی نوازش کا دامن پھیلا دیا ہے.اسلامی نظام عبادت کی ایک دلچسپ خصوصیت اس سمت کے ساتھ تعلق رکھتی ہے جس کی طرف
مسلمانوں کو بوقت نما ز رخ پھیر لینے کا حکم دیا گیا ہے.اگر انہیں کعبے کی صحیح سمت معلوم ہو تو بوقت نماز
وہ قبلہ رو ہو جائیں.تاہم اگر کوئی سفر میں ہو اور اسے کعبے کی سمت کا صحیح پتہ نہ چل رہا ہو تو پھر وہ جس
طرف بھی منہ کر کے نماز ادا کرے گا وہ صحیح سمجھی جائے گی.مزید برآں اگر کوئی شخص کار یا جہاز وغیرہ
میں سفر کر رہا ہے تو قبلہ رو ہونے سے مکمل طور پر رخصت دے دی گئی ہے.یادر ہے کہ اسلامی تعلیم کے مطابق نماز کی ادائیگی کو دوسری ہر بات پر فوقیت حاصل ہے.خواہ
کسی بھی قسم کے حالات ہوں
کسی کو نماز سے ہرگز رخصت نہیں ہے.اگر وضو کیلئے پانی دستیاب نہ ہو تو
تیم اس کا متبادل بن جاتا ہے.ہر کوئی اپنی اپنی سہولت کے مطابق نماز ادا کر سکتا ہے.اگر وہ جسمانی
حرکات نہیں بجالا سکتا اور اشارہ سے بھی نماز پڑھ لے تو اس کی نماز مکمل متصور ہوگی.مثلاً ایک شدید
بیمار
شخص جسمانی حرکات کی بجائے اپنی آنکھوں کو ہلکی سی جنبش دے کر نماز ادا کرسکتا ہے.اُس کیلئے
اس قسم کی نماز بھی مکمل سمجھی جائے گی.بظاہر یہ چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں لیکن کوئی اور مذہب ایسی بار یک تفاصیل میں نہیں گیانہ
ہی کسی مذہب نے اتنی باریکی سے انسانی ضروریات اور حدود کا اس قدر خیال رکھا ہے.اس سے
ثابت ہوتا ہے کہ اسلام ایک عالمگیر اور دائی مذہب ہے جو تمام زمانی یا جغرافیائی حدود سے بالا ہے
اور مرورِ زمانہ کے ساتھ ساتھ اس میں کسی قسم کی تبدیلی کی ضرورت نہیں.حکمرانی در اصل عدل کی ہے.ہر پیر و جواں اور امیر وغریب ایک امام کی اقتدا میں صف بندی
کرتے ہیں.کسی کو بھی اپنی جگہ مخصوص کرنے کی اجازت نہیں بلکہ جو بھی مسجد میں پہلے پہنچے وہ جہاں
چاہے بیٹھ سکتا ہے.کوئی کسی کو اس کی جگہ سے اٹھا نہیں سکتا.سب کیلئے یہ حکم ہے کہ وہ کندھے سے
Page 149
عبادت
میں عدل، احسان اور ایتاء ذی القربیٰ کا مقام
137
کندھا ملا کر کھڑے ہوں.کسی دولتمند کو خواہ اس نے کتنا ہی قیمتی لباس زیب تن کیوں نہ کر رکھا ہو
اجازت نہیں کہ وہ اپنے اور کسی غریب نمازی کے مابین فاصلہ رکھے خواہ وہ غریب چیتھڑوں میں ملبوس
ہو.چنانچہ یوں نہ صرف نماز پڑھنے والوں کو ایک امام کی اقتدا میں نماز ادا کرنے کا حکم ہے بلکہ انہیں
واضح طور پر یہ درس بھی دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا مقام ان کی ظاہری جسمانی حالت
سے قطعاً کوئی تعلق نہیں رکھتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہی زیادہ معزز اور مکرم ہے جو خشیت اللہ اور
تقوی اللہ میں زیادہ بڑھا ہوا ہے.یہ امر فیصلہ کن ہے کہ نمازی کو اس کی ہر نماز کا اجر اس کی باطنی کیفیت کے مطابق دیا جاتا ہے.بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ بظاہر تو تم
سب نے ایک ہی طرح نماز ادا کی ہے لیکن در حقیقت ابوبکر کی ایک نماز تمہاری عام نمازوں سے ستر
گنا بڑھ کر ہے.حضرت
ابوبکر بہت متقی انسان تھے.آپ ہمیشہ بڑے انہماک کے ساتھ نماز ادا
کرتے تھے اور اسی خصوصیت کے حوالے سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں
مذکورہ بالا رائے قائم فرمائی.عبادت کے تعلق میں ایتاء ذی القربی کا بہترین اظہار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
اسوہ حسنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حسن سلوک سے ہوتا ہے.آپ صلی اللہ
علیہ وسلم نے یاد الہی کے حوالے سے اپنی دائمی حالت و کیفیت کو ایک مرتبہ یوں بیان
فرمایا :
تَنَامُ عَيُنِي وَلَا يَنَامُ قَلْبِي.ترجمہ: میری آنکھیں تو سو جاتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا.(7
یہ درجہ یقیناً احسان سے بھی اعلیٰ ہے جسے صرف اور صرف ایتا عذی القربیٰ کا ہی نام دیا جاسکتا
ہے.یہ کیفیت کسی حد تک بعض ماؤں کی اس کیفیت سے مشابہ ہے جو ان کے دلوں میں اپنے
پیارے بچوں کیلئے پائی جاتی ہے کیونکہ بظاہر جب وہ گہری نیند بھی سورہی ہوتی ہیں تو ان کے ذہنوں
میں انہی کا خیال گردش کرتا رہتا ہے.
Page 150
138
عدل، احسان اور ایتاء ذى القربى - حصه دوم
مساجد کی آفاقیت:
وَانَّ الْمَسْجِدَ لِلهِ ( سورة الجن 19:72)
ترجمہ: یقیناً مسجدیں اللہ ہی کیلئے ہیں.مساجد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کیلئے وقف ہیں اور کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ کسی
مومن کو مسجد میں داخل ہونے سے روک دے.تمام عبادت گاہیں جن کا مقصد قیام تو حید ہے ، ان
کے بارہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی نقطہ نظر تھا.آج سے سو سال قبل کی مسلم دنیا کی صورت حال اس سے بالکل متضاد دکھائی دیتی ہے.لگتا ہی
نہیں کہ ان کی مساجد حضرت اقدس محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے نمونے پر بنائی گئی ہیں.وہ تو
فرقوں میں تقسیم تھیں کسی ایک فرقے سے تعلق رکھنے والا دوسرے کی بنائی ہوئی مسجد میں قدم رکھنے کی
ہرگز جرات نہیں کر سکتا تھا.اس سے تو وہ زمانہ یاد آ جاتا ہے جب امریکہ میں گوروں اور کالوں کے
چرچ الگ الگ کر دیئے گئے تھے.کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک حبشی ، گوروں کیلئے مخصوص کسی چرچ
میں داخل ہونے لگا تو اسے سختی سے روک دیا گیا جس سے اُسے سخت دلی صدمہ پہنچا اور وہ وہیں چرچ
کی سیڑھیوں میں بیٹھ گیا اور سسکیاں بھرتے بھرتے نیند کی آغوش میں چلا گیا.کیا دیکھتا ہے کہ
حضرت عیسی علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں آکر اس سے پوچھتے ہیں کہ تم اس طرح بلک بلک کر کیوں
رور ہے ہو؟ اس نے جوا با عرض کیا کہ کیوں نہ روؤں ؟ میں عبادت کی غرض سے چرچ میں داخل ہونا
چاہتا تھا کہ مجھے باہر نکال دیا گیا.اس پر حضرت عیسی علیہ الصلوۃ والسلام نے اُس بے چارے سے
مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا: ” میری طرف دیکھو کہ جب سے یہ چرچ تعمیر ہوا ہے میں نے بھی کبھی
اس میں قدم رکھنے کی جرات نہیں کی تو پھر تو کیوں روتا ہے؟“
عبادت میں اعتدال:
اسلامی عبادت کا ایک اور حسین پہلو یہ ہے کہ رضائے باری تعالیٰ کے حصول کی خاطر اپنی
طاقت سے بڑھ کر عبادت کرنے سے روک دیا گیا ہے.نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سختی اور انتہا
پسندی کی حوصلہ شکنی فرمایا کرتے تھے.چنانچہ فرمایا:
Page 151
عبادت میں عدل، احسان اور ایتاء ذی القربی کا مقام
اپنی جانوں پر ظلم مت کرو.تم سے پہلے لوگ اس لئے تباہ کر دیئے گئے کہ وہ
عبادات میں اپنی طاقت سے بڑھ کر مجاہدے کر کے زبر دستی خدا کو راضی کرنے
کی کوشش کرتے تھے ،، (28)
آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید فرماتے ہیں:
تم اللہ تعالیٰ کو ہر گز نہیں تھکا سکتے.مت خیال کرو کہ عبادت میں ایسی انتہا پسندی
کے ذریعے تم اس پر کسی قسم کا تفوق پالو گے.سوصابر بنو اور اسی قدر عبادت کرو
(29)..139
جس قدر آسانی سے کر سکتے ہو.ایک مرتبہ حضرت اقدس محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے تین صحابہ اس بات پر بحث کر رہے تھے
کہ کثرت عبادت سے حکما روکنے میں کیا حکمت ہے؟ وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ:
" حضرت اقدس محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ایک مقدس انسان ہیں اس لئے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوتو اللہ تعالیٰ نے اپنے کامل رحم کی ضمانت دے رکھی ہے.لیکن ہم جیسے گنہگاروں کیلئے چونکہ ایسی بخشش کی کوئی ضمانت نہیں ہے اس لئے ہم
جتنی زیادہ عبادت کریں گے اسی قدر بخشش کے زیادہ امکانات پیدا ہوں گے.اس انداز سے بحث کے بعد ان میں سے ایک نے یہ عہد باندھا کہ وہ اپنی باقی
ماندہ زندگی رات بھر عبادت میں گزار دے گا.دوسرے صحابی نے عہد کیا کہ وہ
اپنی باقی ماندہ زندگی میں ہمیشہ روزہ رکھے گا اور تیسرے نے تجرد کی زندگی بسر
کرنے کا مصمم ارادہ باندھ لیا.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کا علم ہوا تو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : میں تمہاری نسبت اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرتا
ہوں لیکن میں تو رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں.میں روز ہ بھی رکھتا
ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں اور میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں.پس جو کوئی
میری سنت کی پیروی نہیں کرتا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے.(30)
دوسرا کوئی بھی مذہب واضح طور پر یہ حکم نہیں دیتا کہ نیکی اور عدل کا چولی دامن کا ساتھ ہے.اعمال صالحہ بجالاتے ہوئے ہمیشہ تو ازن قائم رکھنے کی جدو جہد بھی کرنی چاہئے.حد سے آگے نکل
Page 152
140
عدل، احسان اور ایتاء ذى القربى - حصه دوم
جانے میں
کوئی نیکی نہیں ہے.مثال کے طور پر صدقات دینا ایک نیک عمل ہے لیکن یہ نا انصافی ہے
کہ کوئی شخص اپنے خاندان اور زیر کفالت لوگوں کو یکسر نظر انداز کر کے سارا مال و دولت خیرات کر
دے.اسی طرح نماز پڑھنا نیکی ہے لیکن اس سے دوسروں کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہئے.مندرجہ
ذیل حدیث اس نکتے کی خوب وضاحت کرتی ہے:
وو
روایت ہے کہ ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نماز پڑھائی
جیسے آپ بہت جلدی میں ہوں اور معمول سے بہت کم وقت میں نماز مکمل کر
لی.نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ دورانِ نماز میں
نے کسی بچے کے رونے کی آواز سنی.چنانچہ اس کی تکلیف کے خیال سے نماز
مختصر کر دی.(31)..بخاری کتاب الصلوۃ کی ایک روایت کے مطابق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معلوم
ہونے پر کہ ایک امام لمبی نماز پڑھانے کا عادی ہے، ناراضگی کا اظہار فرمایا.(2)
عبادت کی اقسام:
اسلامی نظامِ عبادت ایک اور منفر د خصوصیت کا حامل ہے.اس کی تمام عبادات تین اقسام پر
مشتمل ہیں:
(1) فرائض
(2) سنت اور واجب
(3) نوافل
تمام پنجوقتہ نمازیں انہی تین اقسام پر مشتمل ہیں.مرکزی حصہ ” فرض“ کہلاتا ہے.فرض ہر نماز
کا وہ بنیادی اور مرکزی حصہ ہے جسے کسی بھی حالت میں چھوڑ انہیں جاسکتا.یہ اس بنیادی ڈھانچے
سے مشابہ ہے جس پر ہر زندہ جسم کی تعمیر ہوتی ہے.ساری روحانی زندگی اسی مرکزی نکتے کے گرد گھومتی ہے.پنجوقتہ نمازوں کے کسی بھی فرض کو
چھوڑ دینے سے پوری نماز کالعدم ہو جاتی ہے.سنت ، واجب اور نفل ، نماز میں اس روحانی جسم کیلئے
عضلات، گوشت پوست اور جلد کی حیثیت رکھتے ہیں جنہیں چھوڑ دینے سے فرض نمازیں کمزور
پڑ جاتی ہیں جبکہ ان کی ادائیگی نماز کوحسن ، رنگ اور خوشبوعطا کرتی ہے.نوافل کے بارے میں ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
Page 153
عبادت میں عدل، احسان اور ایتاء ذی القربی کا مقام
(33)..141
ان میں سے ایک نماز ایسی ہے جو بہت اعلیٰ مقام کی حامل ہے.یعنی جورات
کے گہرے اندھیرے میں گہری نیند سے اٹھنے کے بعد ادا کی جاتی ہے.ظاہر ہے کہ اس قسم کا غیر معمولی مجاہدہ صرف وہی شخص کرے گا جسے خاص قرب الہی حاصل
ہے.یہاں اس کی زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں لیکن ہر کوئی یہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ نماز
ایتاً ء ذی القربیٰ کے دائرے سے تعلق رکھتی ہے.قرآن کریم خاص طور پر مندجہ ذیل آیت میں نماز تہجد کی غیر معمولی خصوصیت پر روشنی ڈالتا ہے:
تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا
وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنْفِقُونَ (السجده 17:32)
ترجمہ: ان کے پہلو بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں (جبکہ ) وہ اپنے رب کو
خوف اور طمع کی حالت میں پکار رہے ہوتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا
وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں.سورہ بنی اسرائیل کی مندرجہ ذیل آیت خاص طور پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قرب الہی کے
عظیم ترین مقام کا وعدہ دیتی ہے جو ایتاً عذی القربی کے عمومی تصور سے کہیں بڑھ کر ہے:
وَ مِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا
مَّحْمُودًا
(بنی اسرائیل 80:17)
ترجمہ: اور رات کے ایک حصہ میں بھی اس (قرآن) کے ساتھ تہجد پڑھا کر.یہ تیرے
لئے نفل کے طور پر ہوگا.قریب ہے کہ تیرا رب تجھے مقام محمود پر فائز کردے.
Page 154
142
عدل، احسان اور ایتاء ذى القربى - حصه دوم
13- عدل کا قیام بہر حال ضروری ہے
اب ہم قرآنی تعلیمات کے ایک بالکل مختلف پہلو کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جو ایک طرف تو
افراد کے باہمی تعلق اور دوسری طرف فرد اور معاشرے کے مابین تعلقات سے متعلق ہے.یہ عا
انسانی معاملات میں سیاست کے کردار کا بھی احاطہ کئے ہوئے ہے.اس مضمون پر مختلف زاویہ ہائے
نگاہ سے روشنی ڈالنے والی متعدد قرآنی آیات میں سے ہم نے مندرجہ ذیل چند آیات بغرض وضاحت
چنی ہیں.ان میں سے پہلی آیت ”شہادت“ جیسے اہم مسئلہ سے متعلق ہے.شہادت ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو
حاضر ناظر جان کر نیز عدل کے تمام تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے دینی چاہئے جیسا کہ فرمایا:
يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِ
مَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اِعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ
لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (المائده 9:5)
ترجمہ: اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو! اللہ کی خاطر مضبوطی سے نگرانی کرتے ہوئے
انصاف کی تائید میں گواہ بن جاؤ اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں ہرگز اس بات پر آمادہ نہ
کرے کہ تم انصاف نہ کرو.انصاف کرو یہ تقویٰ کے سب سے زیادہ قریب ہے
اور اللہ سے ڈرو.یقیناً اللہ اس سے ہمیشہ باخبر رہتا ہے جو تم کرتے ہو.پھر فرمایا:
وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمُ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ انَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ
(المائدہ 43:5)
ترجمہ: اور اگر تو فیصلہ کرے تو ان کے درمیان انصاف سے فیصلہ کر.یقیناً اللہ
انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے.مندرجہ ذیل آیت بھی عداوت کی نوعیت پر زور دیتے ہوئے اس مضمون کو آگے بڑھاتی ہے کہ
جن لوگوں نے تمہیں تمہارے بنیادی مذہبی حقوق سے بھی محروم کر رکھا تھا، ان پر غلبہ پالینے کے بعد
ان کی دشمنی کی یاد بھی تمہیں ان کے ساتھ انصاف کرنے سے روک نہ دے چنانچہ فرمایا:
وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
أَنْ تَعْتَدُوا
(المائد3:50)
Page 155
عدل کا قیام بهر حال ضروری ھے
ترجمہ: اور تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس وجہ سے کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے
روکا تھا اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم زیادتی کرو.143
ان آیات میں انسان کی توجہ اس حقیقت کی طرف مبذول کرائی گئی ہے کہ اسے کسی بھی قسم کے
حالات میں عدل و انصاف کا دامن ہاتھ سے نہیں دینا چاہئے اور کسی بھی قسم کے اندرونی یا بیرونی دباؤ
کا شکار ہوئے بغیر ہمیشہ مضبوطی سے عدل پر قائم رہنا چاہئے.
Page 156
144
عدل، احسان اور ایتاء ذى القربى - حصه دوم
14- امانت اور احتساب
قرآن کریم میں استعمال ہونے والا لفظ "امانت" لازماً " احتساب کے مضمون کی طرف
رہنمائی کرتا ہے.یہ ایک المیہ ہے کہ دنیا کے تمام جمہوری ادارے امانت کی اس ذمہ داری کو یکسر
نظر انداز کر دیتے ہیں جس سے انہیں اپنے منتخب کرنے والوں کے سامنے بہر حال عہدہ برآ ہونا
چاہئے.اسی طرح وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی جوابدہ ہیں جس نے ان کے سپر داپنی امانت کی ہے.ان جمہوری معاشروں میں جہاں امانتیں ضائع ہو رہی ہوں نا انصافی اور ظلم کا الزام ایسے اداروں یا
افراد پر ہوتا ہے جو بیک وقت بنی نوع انسان اور اللہ تعالیٰ دونوں سے کئے ہوئے عہدوں کو تو ڑ رہے
ہوتے ہیں.جب بھی کوئی منتخب شدہ تنظیم یا فردا اپنی امانت کا حق ادا نہیں کرتا تو اس کا لازمی نتیجہ مختلف
معاشرتی برائیوں کی صورت میں برآمد ہوا کرتا ہے.چنانچہ انسان عدل و انصاف پر قائم ہونے کی
بجائے جبر و استبداد کا مقابلہ کرتے کرتے فنا ہو جاتا ہے.یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم سای دنیا پر ایک ہی قسم کا طرز حکومت نافذ نہیں کرتا کیونکہ ایسا کرنا
سراسر عدل کے منافی ہے.البتہ قرآن کریم کے مطابق حکومت کے سیاسی نظام میں جمہوریت کو دیگر
تمام نظاموں پر ترجیح دی گئی ہے.اسی طرح قرآن کریم ہر قسم کی حکومت سے تقاضا کرتا ہے کہ وہ اس
احساس کو ہمیشہ مد نظر رکھتے ہوئے اپنی ذمہ داریاں پوری کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور جوابدہ ہے.عوام کیلئے (For the people) کا جمہوری نعرہ ایک مبہم سی بات ہے.قرآن کریم
نے کسی جگہ بھی منتخب شدہ جمہوری حکومتوں کیلئے اس قسم کے الفاظ استعمال نہیں کئے بلکہ ان کی ذمہ
داریوں کے حوالے سے عدل وانصاف پر زور دیا ہے.اس اصول کے مطابق کسی بھی جمہوری ملک میں قانون سازی کا عمل اپنے شہریوں کے حقوق
غصب نہیں کر سکتا خواہ وہ کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں.انہیں بھی دیگر شہریوں کے
مساوی حقوق مہیا کئے جانے ضروری ہیں.سیاسی اکثریت رکھنے والی کسی بھی مجلس قانون ساز کو یہ حق
حاصل نہیں کہ قانون سازی کرتے وقت کسی بھی فرد واحد کے بنیادی حقوق کو پامال کرے.یہ کہ کر
کہ ہم اکثریت کے نمائندہ ہیں ایسی کوئی حرکت کرنا ہرگز قبول نہیں کیا جاسکتا.اس بحث کا ماحصل
بیان کرنے کیلئے ہم مندرجہ ذیل قرآنی آیت پیش کرتے ہیں جو اس گہرے مضمون کو نہایت جامعیت
کے ساتھ پیش فرماتی ہے:
Page 157
امانت اور احتساب
(سورة النساء 4: 59)
اِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأمنتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ
بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا
ترجمہ: یقینا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے حقداروں کے سپرد کیا کرو
اور جب تم لوگوں کے درمیان حکومت کرو تو انصاف کے ساتھ حکومت کرو.یقیناً بہت ہی عمدہ ہے جو اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے.یقیناً اللہ بہت سننے والا
145
( اور ) گہری نظر رکھنے والا ہے.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متواتر عملی نمونے نے اس آیت میں پنہاں حسن کو دوبالا کر دیا
ہے.مومنوں کو نصیحت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ظالم قوموں کے انجام کے
حوالے سے یہ تنبیہ فرمائی:
إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمُ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ
تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ اَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ.وَاَيْمُ اللهِ لَو
أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا.ترجمہ : تم سے پہلے لوگ اس لئے ہلاک ہوئے کہ جب ان کا کوئی بڑا اور بااثر
آدمی چوری کرتا تو اس کو چھوڑ دیتے اور جب کوئی کمزور چوری کرتا تو اس کو سزا
دیتے.خدا کی قسم ! اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی چوری کرتی تو میں اس
کے بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا.(34
اس معاملے میں قرآن کریم نے کسی بھی قسم کا کوئی ابہام نہیں رہنے دیا.چنانچہ کوئی خونی یا ذاتی
تعلق انصاف کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتا.حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے بیٹے کا قصہ
اس امر کی مزید وضاحت کرتا ہے.حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا دیگر منکرین کے ساتھ ہی
غرق ہو گیا تھا کیونکہ اس نے بھی آپ کا انکار کر دیا تھا.تاہم مندرجہ بالا حدیث میں بیان شدہ واقعہ
اور حضرت نوح" کے قصے میں نہایت لطیف فرق ہے.حضرت نوح نے اپنے کافر بیٹے کی نجات
کیلئے دعا کی جو اللہ تعالیٰ نے رد کر دی جبکہ حضرت اقدس محمد مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود یہ
ارادہ ظاہر فرمایا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لینے والے کسی جرم کا
Page 158
146
عدل، احسان اور ایتاء ذى القربى - حصه دوم
ارتکاب کرتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس
کو بھی معاف نہ فرماتے.بعض کا فر کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا محض دعویٰ تھا.اگر آپ صلی اللہ
یہ وسلم کو اپنے کسی قریبی عزیز کے معاملہ میں عدل اور نرمی میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑتا تو
ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور رستہ اختیار کرتے.احادیث کی مستند کتب میں بیان شدہ
مندرجہ ذیل واقعہ ان تمام قیاس آرائیوں کی بکلی نفی کرتا ہے.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چا حضرت عباس رضی اللہ عنہ ہجرت
کے وقت تک مشرف بہ اسلام نہ ہونے کی وجہ سے غزوہ بدر میں قریش مکہ کے
ساتھ تھے اور شکست کے بعد بنائے جانے والے جنگی قیدیوں میں شامل تھے.انہیں بھی دیگر قیدیوں کی طرح مسجد نبوی میں ایک ستون کے ساتھ کس کر باندھ
دیا گیا.یہاں تک کہ آپ شدت تکلیف سے کراہنے لگے.آپ کی کراہنے کی
آواز سن کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو گئے.آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
نیند نہ آرہی تھی اور کروٹوں پر کروٹیں بدلتے جا رہے تھے.چنانچہ آپ صلی اللہ
علیہ وسلم کی بے چینی اور تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے قیدیوں کے نگران نے
حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی رسیاں ڈھیلی کر دیں جس سے انہوں نے
کراہنا اچانک بند کر دیا.ان کے کراہنے کی آواز اچانک بند ہو جانے پر آپ صلی
اللہ علیہ وسلم کی پریشانی اور بڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دریافت کرنے پر
عرض کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کے پیش نظر حضرت عباس رضی اللہ
عنہ کی رسیاں ڈھیلی کر دی گئی ہیں.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر
ناراضگی کا اظہار فرمایا اور حکم دیا کہ اگر عباس کی رسیاں ڈھیلی کر دی گئی ہیں تو پھر
باقی تمام قیدیوں کی رسیاں بھی ڈھیلی کر دی جائیں کیونکہ تمہیں یہ حق نہیں پہنچتا
کہ تم اُن کے ساتھ دیگر قیدیوں کی نسبت کوئی امتیازی سلوک روا رکھو (35)
اس سے ثابت ہوا کہ کیا رشتہ دار اور کیا غیر رشتہ دار، کیا دوست اور کیا دشمن ، آپ صلی اللہ
علیہ وسلم کا سلوک سب کے ساتھ عادلانہ اور یکساں تھا.آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ قرآن کریم کے
اس حکم کی پیروی فرماتے تھے کہ:
Page 159
امانت اور احتساب
147
وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَى الَّا تَعْدِلُوا (المائد: 9:5)
ترجمہ: اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں ہرگز اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم انصاف نہ کرو.یہود اور مسلمانوں کی قدیم دشمنی کو دشمنانِ اسلام نے ہمیشہ ناجائز طور پر اچھالا اور ہوا دی ہے.حالانکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسلمانوں اور یہود کے مابین پیدا ہونے والے اختلافات
کو اس آیت کے تابع کامل عدل کے ساتھ حل فرمایا کرتے تھے.ایسے معاملات میں درج ذیل واقعہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی روشن اور زندہ مثال ہے:
بنونظیر، مدینہ میں آباد ایک یہودی قبیلہ تھا.یہ قبیلہ غزوہ خندق کے دوران اپنے مسلم اتحادیوں
سے غداری اور دھوکہ دہی کی پاداش میں مدینہ سے نکالا جاچکا تھا.اگر چہ طالمو کی تعلیم کے مطابق ان
کے اس سنگین جرم کی سزا صرف اور صرف موت تھی لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر شفقت
فرماتے ہوئے سزائے موت کی بجائے صرف مدینہ بدر کرنے کا حکم صادر فرمایا.چنانچہ وہ مدینہ سے
ہجرت کر کے خیبر کے مقام پر چلے گئے جہاں انہوں نے خیبر کے نام سے ایک نہایت مضبوط قلعہ تعمیر
کیا.طاقت مجتمع کر لینے کے بعد انہوں نے خلاف اسلام سرگرمیوں کا از سر نو آغا ز کر دیا.اس کی
تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں.مختصر یہ کہ ان کا یہ جارحانہ پن بالآخر غزوہ خیبر کے ساتھ ہی
اپنے منطقی انجام کو پہنچ گیا.جنگ سے پہلے جب مسلمانوں کی طرف سے نگران دستے کبھی کبھاراس
علاقہ میں بجھوائے جاتے تھے تو ان میں سے ایک دستے نے ان کی ایک نو آبادی میں لوٹ کھسوٹ کی
اور پھلوں کے کچھ باغات کو بھی نقصان پہنچایا جس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد تکلیف پہنچ
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا.نیز یہ تنبیہ بھی فرمائی کہ:
اللہ تعالیٰ تمہیں اہلِ کتاب کے گھروں میں ان کی اجازت کے بغیر داخل
ہونے کی ہرگز اجازت نہیں دیتا.اسی طرح ان کی خواتین کو قتل کرنا یا باغات
(36)..میں سے پھل توڑنا بھی تمہارے لئے حرام ہے.مختصر یہ کہ ان کی شدیدمذہبی عداوت کے باوجود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم عدل مطلق کی قرآنی
تعلیم پر ختی سے کار بندر ہے.قرآن کریم میں اپنے عزیز رشتے داروں کے خلاف گواہی دینے کے معاملے میں بھی
عدل مطلق کی ہی تاکید ملتی ہے.چنانچہ فرمایا:
Page 160
148
عدل، احسان اور ایتاء ذى القربى - حصه دوم
يَا يُّهَا الَّذِينَ آمَنُوْا كَوْنُوْا قَوْمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى
أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ( النساء 4 : 136)
ترجمہ: اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو! اللہ کی خاطر گواہ بنتے ہوئے انصاف کو
مضبوطی سے قائم کرنے والے بن جاؤ خواہ خود اپنے خلاف گواہی دینی پڑے یا
والدین اور قریبی رشتہ داروں کے خلاف.عدل اور احسان کی اس سے اعلی تعلیم کا تصور بھی ممکن نہیں.یہ اسی تعلیم کا نتیجہ اور آنحضرت صلی
اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی جس نے صحابہ کو اس اعلیٰ وارفع مقام پرفائز کر رکھا تھا کہ گواہی دیتے وقت
خونی رشتوں اور ذاتی تعلقات کو پس پشت ڈال دینا ان کا معمول بن چکا تھا جس کی تائید میں کئی ایک
واقعات پیش کئے جا سکتے ہیں.نہ صرف یہ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ارشادات عالیہ
نے آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی اور کامل غلاموں پر انمٹ نقوش چھوڑے ہیں.ان میں
سے ایک کامل ترین غلام بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں.درج ذیل واقعہ اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے.مرزا سلطان احمد صاحب حضرت مرزا غلام
احمد صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے بڑے بیٹے تھے.وہ آزادانہ نقطہ نظر رکھتے تھے.چنانچہ انہوں نے اپنے والد ماجد کی حیات طیبہ میں احمدیت قبول نہیں کی لیکن بعد میں خلافت ثانیہ
کے دور میں اپنے چھوٹے بھائی ( حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفہ اسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ
عنہ.مترجم) کے ہاتھ پر بیعت کر کے سلسلہ عالیہ احمدیہ میں داخل ہو گئے.خاندانی جائیداد کا نظم و
نسق انہی کے ہاتھ میں تھا.ایک مرتبہ انہوں نے قادیان کے ایک ہندو کے خلاف زمین کے ایک
ٹکڑے پر ناجائز قبضہ کرنے پر مقدمہ کر دیا اور عدالت میں درخواست کی کہ اس پر تعمیر شدہ عمارت کو
مسمار کرنے کی اجازت دی جائے.یہ حقیقت تھی کہ یہ قطعہ اراضی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ
والسلام کی آبائی جائیداد کا حصہ تھا لیکن وکیل استغاثہ نے مقدمہ تیار کرتے ہوئے ایک چھوٹی سی دفعہ
میں ایک جھوٹا جوابی دعوی شامل کر دیا جو بہر حال ایک غلطی تھی.مقصد یہ تھا کہ مقدمہ کو مضبوط کیا
جا سکے لیکن اگر مدعا علیہ اس جھوٹے جوابی دعوے کو باطل ثابت کر دیتا تو مقدمہ لازماً خارج ہو جاتا.عدالت نے اس مقدمہ میں مدعا علیہ کی طرف سے حضرت مرزا غلام احمد علیہ الصلوۃ والسلام کو
بطور گواہ طلب کیا.مدعا علیہ کو یقین تھا کہ آپ جھوٹی گواہی کبھی بھی نہ دیں گے خواہ آپ کو کتنا ہی
نقصان کیوں نہ اٹھانا پڑے.استغاثے کے وکیل نے آپ سے رابطہ کیا اور پوچھا کہ آپ گواہی
Page 161
امانت اور احتساب
149
(37)
کیسے دیں گے؟ جواباً آپ نے فرمایا کہ میں تو سچی گواہی دوں گا خواہ میرے بیٹے اور خاندانی جائداد کا
کتنا ہی نقصان کیوں نہ ہو.وکیل نے یہ بات سن کر فیصلہ کر لیا کہ اس مقدمہ کی مزید پیروی کا کوئی
فائدہ نہیں ہے.چنانچہ اس نے اس مقدمے کی پیروی چھوڑ دی.جماعت احمدیہ کی بنیادرکھنے سے پہلے جب آپ کی عمرتقریبا پچھیں تمہیں برس تھی اور آپ اپنے
والد ماجد کے حکم کے مطابق آبائی جائداد کی دیکھ بھال کرتے تھے تو ان دنوں آپ کے والد اور
مزارعین کے مابین ایک درخت کے کاٹنے پر تنازعہ اٹھ کھڑا ہوا.آپ کے والد محترم نے آپ کو دو
گواہوں کے ہمراہ مقدمہ کی پیروی کیلئے گورداسپور بھیجا.آپ نے اپنے دونوں ساتھیوں سے
مخاطب ہو کر فرمایا کہ والد صاحب بلا وجہ اسے ایک مسئلہ بنا رہے ہیں.درخت بھی تو کھیت کا حصہ
ہی ہوتے ہیں مزار عین غرباء ہیں اگر انہوں نے ایک درخت کاٹ بھی لیا ہے تو کیا حرج ہے؟ میں
یقین سے نہیں کہ سکتا کہ یہ درخت ہماری ملکیت تھا.البتہ یہ ممکن ہے کہ ہمارا بھی اس میں حصہ ہو.مخالفین بھی آپ کی صداقت پر یقین رکھتے تھے چنانچہ مجسٹریٹ کے دریافت کرنے پر انہوں نے
بلا توقف ، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کہا کہ ہماری بجائے آپ مرزا صاحب سے دریافت فرمالیں ، وہ آپ
کو اصل حقیقت سے آگاہ کر دیں گے.چنانچہ آپ سے دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا ” میرے
خیال میں درخت کھیت کا حصہ ہیں اور اس کھیت میں ہم بھی حصہ دار ہیں اور کا شتکار بھی.یہ شہادت
سنتے ہی مجسٹریٹ نے مزارعین کے حق میں فیصلہ دے دیا.جب اس سارے واقعے کی اطلاع آپ
کے والد کو ہوئی تو بہت چیں بہ جبیں ہوئے اور سٹپٹاتے ہوئے بولے ”ملاں ! ملاں! میرا بیٹا تو مولوی
ہے یعنی وہ ضرورت سے زیادہ ہی مذہبی ہے اس لئے اس کو اس احمقانہ حرکت کی سزا ضرور ملنی
چاہیئے.چنانچہ انہوں نے آپ کو گھر سے نکال دیا.آپ کی والدہ ماجدہ آپ کیلئے وہاں
کھانا بھجوایا
کرتی تھیں جہاں آپ پناہ گزین تھے.علم ہونے پر آپ کے والد ماجد نے آپ کی والدہ کو کھانا
بھجوانے سے منع کر دیا.لہذا قادیان میں کچھ عرصہ تکلیف اٹھانے کے بعد آپ بٹالہ تشریف لے گئے
جہاں نہایت کسمپرسی کی حالت میں آپ نے دو ماہ گزارے.بالآخر آپ کے والد محترم کے دل میں
پدری رحم نے جوش مارا اور انہوں نے آپ کو قادیان واپس بلوالیا.ایک مرتبہ کسی شخص نے اپنے گھر سے ملحقہ زمین پر ایک چبوترہ تعمیر کر لیا جو در حقیقت خاندان
حضرت مسیح موعود علیہ الصلواۃ والسلام کی ملکیت تھی لیکن چونکہ سالہا سال سے وہ آدمی اس پر قابض تھا
اور اسے استعمال کر رہا تھا اس لئے عملاً وہ اسی کی ملکیت متصور ہوتی تھی.چنانچہ آپ کے بڑے بھائی
*(38)
Page 162
150
(39)
عدل، احسان اور ایتاء ذى القربى - حصه دوم
نے اس کی ملکیت دوبارہ حاصل کرنے کیلئے قانونی چارہ جوئی کی.ایسے مقدمات کی روایت کے
مطابق انہوں نے بھی بالکل ایک جھوٹا مقدمہ درج کروا دیا.دعوی یہ تھا کہ مالک مکان طویل عرصہ
سے اس زمین پر قابض نہیں تھا بلکہ حال ہی میں اس پر قابض ہوا ہے.مالک مکان کے پاس اپنی طویل
ملکیت ثابت کرنے کا کوئی رستہ نہ تھا.اس کے پاس اپنے دفاع کا صرف ایک ہی ذریعہ تھا.جواب
دعوی میں اس نے کہا کہ میں کسی اور گواہ کو پیش نہیں کرنا چاہتامدعی کے چھوٹے بھائی کی گواہی میرے لئے
کافی ہوگی اور مجھے ہر حال میں قبول ہو گی.عدالت نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بلا کر
پوچھا کہ کیا آپ کے علم میں ہے کہ متنازعہ جگہ پچھلے چند سال سے مد عاعلیہ اور اس کے خاندان کے
زیر استعمال ہے؟ آپ نے اثبات میں جواب دیا.جس کے نتیجہ میں عدالت نے مقدمہ کا فیصلہ آپ
کے بھائی کے خلاف کر دیا.(9)
جماعت احمدیہ کیلئے یہ بات انتہائی اعزاز کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی اخلاقی برتری کو دوبارہ
ثابت کرنے کیلئے انہیں چنا ہے.اگر چہ جماعت کے ہر فرد کیلئے روحانیت کے ایسے مدارج پالینا ممکن
نہیں پھر بھی بحیثیت جماعت ان کیلئے اسلام کے روحانی اور اخلاقی حسن کا علمبر دار ہونا ممکن ہے.جب احمدی احیائے اسلام کی بات کرتے ہیں تو اس سے ہرگز یہ مراد نہیں ہوتی کہ تاریخ اسلام
میں کوئی دور ایسا بھی آیا تھا کہ جب اسلامی اقدار سرے سے ہی نا پید ہوگئی ہوں بلکہ اس سے صرف
اتنی مراد ہے کہ ہر اگلی نسل اس سر چشمہ کے حقیقی حسن سے دور ہٹ کر تنزل کا شکار ہوتی چلی گئی.احمدیت کا بنیادی مقصد مسلمانوں کے کھوئے ہوئے بلند مقام کو دوبارہ حاصل کرنا ہے.اسلام
کو دائی زندگی عطا کرنے کیلئے انہیں اپنی جان کی قربانی دینے سے بھی دریغ نہیں کرنا چاہئے.
Page 163
مسلمانوں اور غیر مسلموں کی ایک دوسرے کے خلاف شهادت
151
15- مسلمانوں اور غیر مسلموں کی ایک دوسرے کے خلاف شہادت
شہادت کے معنوں کا ایک پہلو جو اس دور میں بہت اہمیت حاصل کر چکا ہے وہ مسلمانوں اور
غیر مسلموں کی شہادت کی صحت ہے.بہت سے جدید مسلم علماء یہ کہ کر اسلام کے ساتھ سخت نا انصافی
کرتے ہیں کہ اسلام کسی مسلمان کے خلاف غیر مسلم کی شہادت
تسلیم نہیں کرتا جبکہ کسی بھی غیر مسلم کے
خلاف مسلمان کی گواہی ہمیشہ تسلیم کی جانے چاہئے.اپنی اس دلیل کے حق میں وہ بعض متعلقہ آیات
قرآنی کا ایسا ترجمہ کرتے ہیں جسے نہ تو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ثابت کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی
مقدس بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے.در حقیقت ان کا دعویٰ یہ ہے کہ اسلام
کے نزدیک عدل کا دائرہ کار صرف اور صرف مسلمانوں کے مقاصد کی تکمیل تک محدود ہے.ان کے
نزدیک اگر انصاف کا یہی تصور ہے تو پھر نا انصافی کا دور دورہ ہوگا اور عدل و انصاف کا جنازہ ہی نکلے
گا.لیکن قرآن کریم جس عدل کے قیام کی تاکید فرماتا ہے اسے کبھی بھی فنا نہیں ہے.فرماتا ہے:
وَقُلْ أَمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ مِنْ كِتَبٍ ۚ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ
اللهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ
بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اللهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ
(الشورای 16:42)
ترجمہ: اور کہہ دے کہ میں اس پر ایمان لا چکا ہوں جو کتاب ہی کی باتوں
میں سے اللہ نے اتارا ہے.اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان
انصاف کا معاملہ کروں.اللہ ہی ہمارا رب اور تمہارا بھی رب ہے.ہمارے
لئے ہمارے اعمال اور تمہارے لئے تمہارے اعمال ہیں.ہمارے اور تمہارے
درمیان کوئی جھگڑا ( کام ) نہیں ( آسکتا).اللہ ہمیں اکٹھا کرے گا اور اسی کی
طرف لوٹ کر جانا ہے.مذکورہ بالا آیت میں صرف مسلمانوں کو ہی نہیں بلکہ سارے بنی نوع انسان کو مخاطب کیا گیا ہے جس
میں مختلف مذاہب عالم کے پیرو کار شامل ہیں.آیت کریمہ بیان کر رہی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
اس درجے کے امین ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کا مکمل
اختیار بخشا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کسی کے ساتھ نا انصافی نہیں کر سکتے.ایک طرف تو
Page 164
152
عدل، احسان اور ایتاء ذى القربى - حصه دوم
ہمارے سامنے یہ مستند اسلامی تعلیم موجود ہے اور دوسری طرف دقیانوسی قسم کے تقلید پسند ملاں ہیں جو
دنیا کو یہ کہ کر گمراہ کر رہے ہیں کہ اسلام کسی مسلمان کے خلاف غیر
مسلم کی گواہی ہرگز قبول نہیں کرتا لیکن
اس کے برعکس غیر مسلم کے خلاف مسلمان کی گواہی قابل قبول ہے.افسوس ناک امر تو یہ ہے کہ آج
مسلمانوں کی بھاری اکثریت شہادت کے اعلیٰ اسلامی معیار پر پوری ہی نہیں اترتی.اس کے باوجود علما کے خیال میں ایک بددیانت مسلمان کی گواہی ایک دیانتدار غیر مسلم کی
شہادت کی نسبت زیادہ معتبر ہے.اپنے اس بگڑے ہوئے اعتقاد کی تائید میں وہ کئی ایک قرآنی
آیات بھی پیش کرتے ہیں.انہی آیات کے حوالے سے میں ان کے دلائل کا بطلان ثابت کروں گا.اپنے مؤقف کی تائید میں وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 283 پیش کرتے ہیں جس میں ہدایت
کی گئی ہے کہ:
اور اپنے مردوں میں سے دو کو گواہ ٹھہرالیا کرو ملاں اس آیت کی غلط تشریح کرتے ہوئے
اس سے صرف مسلمان مراد لیتے ہیں.حیرت کی بات تو یہ ہے کہ علماء سمجھ ہی نہیں پائے کہ اس آیت کا اطلاق چھوٹی چھوٹی مجرمانہ حرکات
جیسے روزمرہ واقعات یا حادثات پر نہیں ہوتا.ایسے معاملات میں موقع کے گواہوں کی موجودگی ایک
اتفاق ہے.ان کے مذہب کا یا صنف کا اس سے کیا تعلق ہوا؟ بلکہ بعض اوقات کسی واقعہ کا کوئی بھی گواہ
موجود نہیں ہوتا یا پھر کسی واقعہ کی عینی شاہد صرف ایک عورت ہی ہوتی ہے.چنانچہ کسی خاص موقع کی
مناسبت سے وضع کئے گئے قانون کو بلا سوچے سمجھے اور بغیر کسی مناسب ثبوت کے عموم پر محمول کرنا ،
قرآن کریم کے ساتھ سخت نا انصافی ہے.یہی مضمون ایک اور جگہ زیر بحث لایا گیا ہے کہ:
وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَاَقِيْمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ (الطلاق 3:65)
ترجمہ: اور اپنے میں سے دو صاحب انصاف ( شخصوں ) کو گواہ ٹھہر الو اور اللہ
کیلئے شہادت کو قائم کرو.اس آیت کو بھی علما اپنے اس عقیدہ کی تائید میں پیش کرتے ہیں کہ گواہوں کا مسلمانوں میں
سے ہونا ضروری ہے.ان کی دلیل یہ ہے کہ : ” تم میں سے مراد مسلمان ہیں کیونکہ وہی اس آیت
کے مخاطب ہیں.66
اگر ان کا یہ استنباط درست ہے تو پھر اس آیت کے کیا معنی ہوں گے جس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ
اگر مسلمانوں میں سے گواہ میسر نہ ہوں تو غیر مسلموں میں سے گواہ تلاش کر لئے جائیں.
Page 165
مسلمانوں اور غیر مسلموں كى ايك دوسرے کے خلاف شهادت
يَايُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ
حِيْنَ الْوَصِيَّةِ اثْنَنِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ أَخَرَنْ مِنْ
غَيْرِكُمْ إِنْ اَنْتُمُ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمُ
مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ
( المائد 107:50)
ترجمہ: اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو! جب تم میں سے کسی تک موت آپہنچے تو
تمہارے درمیان شہادت کے طور پر وصیت کے وقت اپنے میں سے دو
صاحب عدل گواہوں کا تقر ر ضروری ہے.البتہ اگر تم زمین میں سفر کر رہے ہو
اور تمہیں موت کی مصیبت آلے تو اپنوں کی بجائے غیروں میں سے دو گواہ بنا
سکتے ہو.153
ذراسی عقل رکھنے والا بھی بخوبی جان سکتا ہے کہ ایک مسلمان کی گواہی غیر
مسلم کی گواہی کی نسبت
اصولاً زیادہ معتبر شمار نہیں کی جاتی.ہاں مسلم معاشرے میں داخلی معاملات پر فیصلہ کرتے وقت اگر
گواہوں کی ضرورت پڑ جائے تو یہ فطرتی امر ہے کہ مسلمانوں میں سے گواہ طلب کئے جائیں گے.لیکن
اگر کوئی سفر پر ہوتو پھر ایک غیر مسلم کی گواہی بھی ویسی ہی معتبر ہوگی جیسی ایک مسلمان کی ہوتی ہے.مذکورہ بالا دونوں آیات بطور خاص مالی معاملات سے تعلق رکھتی ہیں لہذا کسی کو بھی یہ حق حاصل نہیں
کہ ان
کو عموم پر محمول کرے اور نہ ہی یہ روز مرہ حادثات اور جرائم وغیرہ کے واقعات پر اطلاق پاتی ہیں.ایک اور بنیادی اصول یہ بھی ذہن میں مستحضر رہنا چاہئے کہ کسی بھی قرآنی آیت کا ایسا تر جمہ جو
کسی اور قرآنی آیت یا حضرت اقدس محمد مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے متصادم ہو ہرگز قابلِ
قبول نہیں.مسلم اور غیر مسلم کی شہادت کے متعلق اختلاف کو طے کرنے کا آسان اور بہترین طریق یہ ہے
کہ معاملے کی جانچ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور کردار کی کسوٹی پر کی جائے.قرآن کریم
کی کوئی بھی ایسی تشریح جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرۃ وسوانح کے عین مطابق ہو قبول کر لی
جائے اور جہاں دونوں میں بظاہر تقضاد دکھائی دے تو کوئی بھی نتیجہ اخذ کرنے سے پہلے مزید تحقیق کر
لی جائے.آئیے ایک واقعہ کا تجزیہ کریں جو کہ سنن ابو داؤد میں درج ہے.اس سے معلوم ہوگا کہ زیر
غور معاملے کی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تشریح فرمائی تھی اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا
طرز عمل قرآن کریم کی عملی تفسیر تھا.
Page 166
154
عدل، احسان اور ایتاء ذى القربى - حصه دوم
حضرت اشعث رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک قطعہ اراضی
پر میرا ایک یہودی کے ساتھ تنازعہ تھا.ہمارا مقدمہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ
علیہ وسلم کے حضور پیش ہوا.آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے جگہ کی ملکیت کا
ثبوت مانگا لیکن میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا.تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہودی کو مخاطب کر کے فرمایا: ” تم چونکہ مدعا علیہ ہو اس لئے تمہیں حلف دینا ہو
گا.کیا تم حلفاً کہ سکتے ہو کہ یہ زمین تمہاری ملکیت ہے؟‘اشعث رضی اللہ عنہ
کہتے ہیں کہ میں نے احتجاجا عرض کیا: ”اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ! یہ
تو یہودی ہے اور جھوٹی قسم اٹھا کر میری جائداد پر قبضہ کر لے گا.“
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ” لیکن اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی تو
نہیں.میرا فیصلہ تو انصاف پر ہی مبنی ہوگا.اور پھر یہودی کو مخاطب کر کے
فرمایا: ” خوف خدا دل میں رکھ کر حلف دو کہ یہ جگہ واقعی تمہاری ہے.اگر تم حلف
(40)..دے دو تو میرا فیصلہ تمہارے حق میں ہوگا.مندرجہ ذیل واقعہ اس بات کا اور بھی زیادہ روشن ثبوت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی
قوانین کا کیا مفہوم سمجھتے تھے.ایک مرتبہ چند مسلمانوں نے بعض کاموں کی غرض سے خیبر کا سفر اختیار
کیا.رستے میں انہیں ایک مقتول مسلمان کی نعش ملی.اس علاقے میں کوئی مسلمان آباد نہ تھا بلکہ
صرف یہود آباد تھے جس کا صاف مطلب یہی تھا کہ قاتل کوئی یہودی ہی ہے.چنانچہ مسلمانوں نے
اس علاقے کے یہود کو بھی بحیثیت مجموعی اس قتل کا ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے یہ موقف اختیار کیا کہ اس
علاقے میں آباد یہو دل کر قصاص کی رقم مقتول کے ورثاء کو ادا کریں.جب یہ مقدمہ آنحضرت صلی
اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
وو
یہ ایک نہایت سنجیدہ معاملہ ہے.لیکن کیا تمہارے پاس کوئی ایسا ٹھوس اور
واضح ثبوت ہے جس سے تمہارے اس دعوے کی تصدیق ہوتی ہو کہ قاتل واقعہ
کوئی یہودی ہی ہے؟
مسلمانوں نے عرض کیا یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ! گواہ تو کوئی بھی نہیں ہے.چنانچہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود سے حلف نامہ لکھوانے کا فیصلہ فرمایا.جس پر مسلمانوں نے عرض
Page 167
مسلمانوں اور غیر مسلموں کی ایک دوسرے کے خلاف شهادت
155
کیا کہ وہ جھوٹی قسم اٹھا لیں گے.لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی طرف سے اٹھائے
جانے والے اس اعتراض پر خفگی کا اظہار فرمایا اور یہود سے حلف نامہ لے کر تفتیش کا سلسلہ وہیں
روک دیا.لیکن مقتول کے ورثاء چونکہ خون بہا کے حقدار تھے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قومی
مال میں سے انہیں رقم ادا کر دی.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم عدل کے ساتھ ایک طبعی وابستگی رکھتے تھے اور یہ واقعہ اس کی ایک
زندہ مثال ہے.تا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ چونکہ اُن شواہد کی بنا پر کیا تھا جو مہیا ہو سکے تھے
اس لئے امکان ضرور موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ محض قانونی طور پر ہی درست ہو.عین
ممکن ہے کہ کوئی چرب زبان شخص اپنا موقف اپنے مؤثر انداز میں پیش کرے کہ باوجود انصاف کے
تمام تقاضے پورے کرنے کے قاضی کسی غلط نتیجے پر جا پہنچے.اندر میں صورت انصاف کا خون کرنے
کی ذمہ داری بددیانت وکیل پر ہوگی نہ کہ قاضی پر.چنانچہ اسی امکان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے
حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَّ إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَ لَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ
اَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضِ فَاقْضِيَ عَلَى نَحْوِمَا أَسْمَعُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ
بِحَقِّ اَخِيْهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذُهُ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِّنَ النَّارِ.ترجمہ: میں بھی انسان ہوں اور تم میرے پاس جھگڑا لے کر آتے ہو.ممکن ہے
کہ کوئی آدمی تم میں سے دوسرے کی نسبت زیادہ عمدہ انداز میں اپنی بات کو پیش
کر سکتا ہو.پس اگر میں اس کی باتوں سے متاثر ہو کر اس کے حق میں فیصلہ
کر دوں اور اس کے بھائی کے حق میں سے اسے کچھ دلا دوں تو اسے یہ نہیں لینا
(41)
چاہئے کیونکہ اس کے لئے وہ آگ کا ایک ٹکڑا ہے جو میں اسے دلا رہا ہوں.(
قابل ذکر امر یہ ہے کہ مضبوط وکالت اور مہیا کردہ شواہد کی بنا پر اگر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ
وسلم سے بھی جھوٹے کے حق میں فیصلہ کروایا جا سکتا ہے تو ایسی صورت میں غلط فیصلہ کی تمام تر ذمہ
داری غلط فیصلہ کروانے والے پر ہوگی کیونکہ وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ غاصب کون ہے.اسی لئے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے متنبہ فرمایا ہے کہ اگر غصب کردہ جائداد اس کے حقیقی مالک کو نہ لوٹائی
گئی تو با وجود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے غاصب اللہ تعالیٰ کے حضور جوابدہ ہو گا.مندرجہ
ذیل واقعہ اس امر کی مزید تائید کرتا ہے:
Page 168
156
عدل، احسان اور ایتاء ذى القربى - حصه دوم
ایک سفر کے دوران کسی جگہ پر جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم
سفر صحابہ نے پڑاؤ کیا تو کسی مسلمان کے ہتھیار چوری ہو گئے.بات آگے بڑھی تو آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے سارے کیمپ کی تلاشی کا حکم دے دیا.چوری کا ارتکاب تو در حقیقت کسی مسلمان نے ہی
کیا تھا لیکن جب تلاشی شروع ہوئی تو اس نے چالا کی سے وہ ہتھیار ایک یہودی کے سامان کے
ساتھ رکھ دیئے اور وہیں سے ہتھیار برآمد ہوئے جس کے نتیجے میں قریب تھا کہ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم اس یہودی کو سزا سناتے کہ یہ آیت نازل ہوئی:
إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَيكَ
الله وَلَا تَكُن لِلْخَاسِنِينَ خَصِيْمًا (النساء 4: 106)
ترجمہ: ہم نے یقیناً تیری طرف کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے تا کہ تو
لوگوں کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کرے جو اللہ نے تجھے سمجھایا ہے اور
خیانت کرنے والوں کے حق میں بحث کرنے والا نہ بن.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وحی الہی سے فورا بھانپ لیا کہ اگر چہ بظاہر یہودی ہی مجرم
دکھائی دیتا ہے لیکن حقیقت کچھ اور ہی ہے.یعنی اس جرم کا مرتکب کوئی یہودی نہیں بلکہ مسلمان ہے.چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید تحقیقات کا حکم دیا جس کے نتیجے میں اصل مجرم پکڑا گیا.اس آیت سے واضح ہے کہ شہادت کے اسلامی اصول کے مطابق نہ تو اس بات کی کوئی اہمیت
ہے کہ گواہ کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے اور نہ ہی اس بات کی کہ نتیجے کا خمیازہ کسی مسلمان
کو بھگتنا پڑتا
ہے یا غیر مسلم کو.افسوس صد افسوس! کہ عصر حاضر کے مسلم علماء عدل کی راہ سے کس قدر دور جا پڑے ہیں.اور
جہاں تک شہادت کے معاملے میں انصاف کا تعلق ہے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قول و فعل
ہمیشہ سیکولر اور غیر جانبدارانہ رہا ہے.یہ تو بعد کے علمانے اپنی فطرتی کجی کے باعث اسلامی تعلیمات
میں بھی بگاڑ پیدا کرنے کی مذموم کوشش کی ہے.چنانچہ میں نہ صرف احمد یوں بلکہ مسلمانانِ عالم کو دعوت دیتا ہوں کہ اسلام اور اس کے مقدس
آقاصلی اللہ علیہ وسلم کی پاک تعلیمات پر حملہ آور ہونے والی ہر نا پاک کوشش کے خلاف جہاد کیلئے اٹھ
کھڑے ہوں اور اس راہ میں اپنی جان مال اور عزت و آبر و غرض کسی بھی چیز کی پرواہ نہ کریں.یاد
رکھو کہ آج صرف دشمن ہی اسلام پر بڑھ بڑھ کر حملے نہیں کر رہا بلکہ ظلم کی حد تو یہ ہے کہ نام نہاد مسلمان
Page 169
مسلمانوں اور غیر مسلموں كى ايك دوسرے کے خلاف شهادت
157
علماء بھی اسلام کی پیٹھ میں چھرا گھونپ رہے ہیں.پس ہمیں اپنے مقدس آقاصلی اللہ علیہ وسلم کی
طرف چلائے جانے والے ہر ایک تیر کو بڑی جرات سے اپنے سینوں پر لینا ہوگا کیونکہ راہ مولیٰ میں
جان دینے سے افضل کوئی موت نہیں ہو سکتی.آخر میں میں آپ سے دعا کی درخواست کرتا ہوں کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا فضل،
احسان اور اس کی رحمت ہے کہ اس نے ہر ایک شر اور بدنظمی سے ہمیں بچایا اور اس قدر پر سکون روحانی
فضا میں اپنی تائید و نصرت کے نظارے دکھائے.دنیا کے کونے کونے سے عاشقانِ محمد مصطفی صلی اللہ
علیہ وسلم یہاں جمع ہوئے ہیں.جب وہ یہاں آنے کیلئے سفر کر رہے تھے تو بھی ان کے دل اللہ تعالیٰ
کی حمد کے گیت گاتے رہے اور اب جبکہ وہ اپنے اپنے گھروں کو واپس جانے والے ہیں تو چاہئے کہ
اللہ تعالیٰ کی حمد وثناء کے گیت گاتے ہوئے جائیں.آپ لوگوں کی جدائی کا سوچ کر میرا دل بھر آ گیا ہے.میری دعا ہے کہ اس سفر میں اللہ تعالیٰ
آپ کا حامی و ناصر ہو.غالب کی زبان میں ہیں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ :
وداع و وصل جداگان لذتی دارد
ہزار بار برو
صد ہزار بار بیا
یعنی ہجر اور وصال دونوں کا اپنا اپنا لطف ہے لیکن شاعر اپنے محبوب سے التجا کرتا ہے کہ تم مجھے
سے ہزار بار جدا ہو جاؤ لیکن سو ہزار مرتبہ لوٹ کر واپس آؤ.اسی طرح میں اپنے پیارے احمدیوں سے
یہ کہتا ہوں کہ انہیں ہزار مرتبہ جدا ہونا ہے لیکن صرف اس لئے کہ دس ہزار بارلوٹ کر آنا ہے.اللہ کرے کہ ہم خدا تعالیٰ کے نام کی بلندی کی خاطر ہمیشہ یہاں اکٹھے ہوتے رہیں اور ہمیشہ
اس کی محبت کے چراغ روشن کرتے چلے جائیں اور ہمیشہ اسی طرح حضرت اقدس محمد مصطفی صلی اللہ
علیہ وسلم پر درود وسلام پڑھتے رہیں اور اللہ کرے کہ پیار محبت کی یہ فضا ہمیشہ بڑھتی اور پھلتی پھولتی
رہے اور کل عالم کو اپنی لپیٹ میں لے لے.( آمین ثم آمین )
Page 170
158
عدل، احسان اور ایتاء ذى القربى - حصه دوم
حوالہ جات حصہ دوم
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
صحیح بخاری، کتاب البيوع، بابُ شِرَاءِ المَمْلُوكِ من الحَرْبِى و هِبَتِهِ و عِتقه، روایت نمبر 2220.مولف:ابوعبدالله محمد بن اسماعیل البخاري الجعفی.ناشر: دار السلام للنشر والتوزيع، الرياض،
الطبعة الثانية ذو الحجة 1419ه، مارچ 1999ء
الطبقات الکبری، جلد 1 صفحه 128 129.مولف : محمد بن سعد بن منيع الزهرى.ناشر: داراحیاء التراث العربي، بيروت، لبنان الطبعة الاولى 1417ه، 1996ء
صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب تحریم قتل الكافر بعد قوله : لا اله الا الله، روایت نمبر 277.تالیف: ابوالحسین مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابورى.ناشر: دارالسلام للنشر والتوزيع، الطبعة الاولى، بيع الاول 1419ه، جولائی 1998ء
جامع الترمذی، ابواب تفسیر القرآن، باب و من سورة آل عمران.روایت نمبر 3010.مولف: ابوعیسی محمد بن عيسى بن سورة ابن موسى الترمذى.ناشر: دارالسلام للنشر والتوزيع، الطبعة الاولى، محرم 1420ه.اپریل 1999ء.مسند احمد بن حنبل، جلد 1 صفحه 153.تالیف : ابو عبدالله احمدبن حنبل.ناشر: دار الفكر.الترغيب والترهيب من الحديث الشريف، جلد 4 ، صفحه 152 ، كتاب التوبة والزهد.الترغيب في
الفقر وقلة ذات اليد، وماجاء في فضل الفقراء والمساكين والمستضعفين.....تاليف: امام حافظ زکی الدین
عبدالعظیم بن عبدالقوى المنذری ناشر: دار احیاء التراث العربی، بیروت، لبنان الطبعة الثالثه 1388
اصحاب ،احمد جلد 4 صفحه 172 ، 173.مولف : ملک صلاح الدین صاحب ایم اے.شائع کردہ: صلاح الدین ملک ایم اے قادیان(پنجاب)بھارت.جامع ترمذی،کتاب الدعوات،باب ماجاء في عقد التسبيح باليد.روایت نمبر 3487.مولف: ابوعیسی محمد بن عيسى بن سورة ابن موسى الترمذى.ناشر:دارالسلام للنشر والتوزيع، الطبعة الاولى.محرم 1420ه.اپریل1999ء.نور القرآن صفحه 62 ، مصنف حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مهدی معهود.روحانی خزائن جلد 9صفحه 437.نظارت اشاعت ربوه پاکستان مطبع: ضیاء الاسلام پریس ربوه.نورالقرآن صفحه 63 مصنف حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعودو مهدی معهود
روحانی خزائن جلد 9 صفحه 438.نظارت اشاعت ربوه پاکستان مطبع: ضیاء الاسلام پریس ربوه.نور القرآن، صفحه 63تا64.مصنف: حضرت مرزا غلام احمد قادیانی، مسیح موعودومهدی معهود
روحانی خزائن جلد 9 صفحه 438 تا 439.نظارت اشاعت ربوه پاکستان مطبع: ضیاء الاسلام پریس ربوه.نور القرآن،صفحه64 تا 65 مصنف حضرت مرزا غلام احمد ،قادیانی، مسیح موعودو مهدی
معهود روحانی خزائن جلد 9صفحه439 تا 440.نظارت اشاعت ربوہ پاکستان.مطبع: ضیاء
الاسلام پریس ربوه.البقرة 201:2
*
Page 171
159
نور القرآن،صفحه 440.مصنف: حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعودو مهدی معهود
روحانی خزائن جلد 9 صفحه 440.نظارت اشاعت ربوه.پاکستان.مطبع: ضیاء الاسلام پریس
ربوه.* البقرة208:2
جامع ترمذی، کتاب الصلوة ، باب ما جاء فى القراءة بالليل روائيت نمبر 447.مولف: ابوعیسی
محمد بن عيسى بن سورة ابن موسى الترمذى ناشر: دار السلام للنشر والتوزيع، الطبعة الاولى.محرم 1420ه.اپریل 1999 ء
صحیح بخاری، کتاب الاذان، باب رفع الصوت بالنداء، روايت نمبر 609.مولف:ابوعبدالله
محمد بن اسماعيل البخاري الجعفي ناشر: دار السلام للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة الثانية
ذو الحجة 1419ه ، مارچ 1999ء.صحیح بخاری،کتاب المناقب،باب كان النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه،
روایت نمبر 3569.مولف: ابو عبدالله محمد بن اسماعيل البخاري الجعفي.ناشر: دار السلام
للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة الثانية ذو الحجة 1419ه ، مارچ 1999ء
سنن ابو داؤد، کتاب الادب، باب فى الحسد، روایت نمبر 4904 مولف: ابو داؤد سلیمان بن
الاشعث بن اسحاق الازدى السجستاني ناشر: دار السلام للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة
الاولى.محرم 1420ه.اپریل 1999 ء
"
صحیح بخاری، کتاب التهجد، باب ما يكره من التشديد فى العبادة، روايت نمبر 1151.مولف: ابو عبدالله محمد بن اسماعيل البخاري الجعفى.ناشر: دار السلام للنشر والتوزيع، الرياض،
الطبعة الثانية ذو الحجة 1419ه ، مارچ 1999ء مشكوة المصابيح كتاب الصلوة،باب القصد
في العمل الفصل الاول.روایت نمبر 1243.تاليف : ابو عبدالله محمد بن عبدالله الخطيب التبريزى.ناشر: دار الكتب العلمية، بيروت لبنان الطبعة الاولى.1424ه.2003 ء
صحیح بخاری، کتاب النکاح باب الترغيب فى النكاح.روايت نمبر 5063.مولف:ابوعبدالله
محمد بن اسماعيل البخاري الجعفي ناشر: دار السلام للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة الثانية
ذو الحجة 1419ھ ، مارچ 1999ء.صحیح بخارى، كتاب الاذان، باب مَنْ اَخَفَّ الصلوة عندبُكاءِ الصبي.روايت نمبر 708.مولف: ابوعبدالله محمد بن اسماعيل البخاري الجعفى ناشر: دار السلام للنشر والتوزيع،
الرياض، الطبعة الثانية ذو الحجة 1419 ، ، مارچ 1999ء
صحیح بخاری، کتاب الاذان، باب مَنْ شكا امامه اذا طَوَّل روایت نمبر 704.مولف:ابوعبدالله
محمد بن اسماعيل البخاري الجعفي ناشر: دار السلام للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة الثانية
ذو الحجة 1419ه، مارچ 1999ء
صحیح مسلم، كتاب الصيام، باب فضل صوم المحرم.روایت نمبر 2755.تاليف: امام ابوالحسين
مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيرى النيسابورى ناشر: دار السلام للنشر والتوزيع، الرياض..طبع اوّل: 1419ھ ، جولائی 1998ء
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
Page 172
عدل، احسان اور ایتاء ذی القربى - حصه دوم
صحیح بخاری، کتاب احادیث الانبياء، باب حديث الغار، روایت نمبر 3475.مولف:ابوعبدالله
محمد بن اسماعيل البخاري الجعفى.ناشر: دار السلام للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة الثانية
ذو الحجة 1419ھ ، مارچ 1999ء.صحیح مسلم، كتاب الحدود، باب قطع السارق الشريف وغيره، روایت نمبر 4410.تالیف: امام ابو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيرى النیسابوری.ناشر: دار السلام
للنشر والتوزيع، الرياض.طبع اوّل : 1419ھ ، جولائی 1998ء
الطبقات الکبری، جلد نمبر 4 صفحه 325 مولف : محمد بن سعد بن منيع الزهرى.ناشر: دار احياء
التراث العربي، بيروت، لبنان الطبعة الاولى.1417ه ، 1996ء.سنن ابو داؤد، كتاب الخراج والفئ والامارة، باب في تعشير اهل الذمة اذا اختلفوا بالتجارة،
روایت نمبر 3050.مولف: ابو داؤد سلیمان بن الاشعث بن اسحاق الازدى السجستاني.ناشر: دار السلام للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة الاولى.محرم 1420ه.اپریل 1999ء.آئینه کمالات اسلام صفحه 299 تا 300.مصنف حضرت مرزا غلام احمد قادیانی، مسیح موعود
مهدى معهود عليه السلام روحانی خزائن جلد 5 صفحه 299 تا 300.تاریخ احمدیت جلد 1 ، صفحه 72 تا 73.مولف: دوست محمد شاهد.بحواله روایت میان الله
:
یار صاحب ٹھیکیدار از روایات صحابه جلد 9 صفحه 192 تا 194.تاریخ احمدیت ، جلد 1، صفحه 74.مولف: دوست مـحـمـدشـاهـد.بحواله: الفضل قاديان
دارالامان.24 اگست 1936 ، جلد 24،نمبر 49،صفحه 3 تا4.صحیح بخاری، کتاب الشهادات،باب سوال الحاکم المدعی: هل لک بینة؟روایت نمبر 2667.مولف: ابوعبدالله محمد بن اسماعيل البخاري الجعفی ناشر: دار السلام للنشر والتوزيع، الرياض،
الطبعة الثانية ذو الحجة 1419ه، مارچ 1999ء
صحیح بخاری، کتاب الاحكام، باب موعظة الإمام للخصوم.روايت نمبر 7169.مولف: ابو عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري الجعفي.ناشر: دار السلام للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة الثانية ذو الحجة 1419ه ، مارچ 1999ء.احكام القرآن للجصاص، جزء ثاني، صفحه 279 مولف: ابوبکر احمد بن على الرازي الجصاص
الحنفى،سهیل اکیڈمی ، لاهور، باکستان.تفسیر آیت: انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحكم بين
الناس بما اراك الله....ولاتكن للخائنين خصيماً.(النساء:106)
160
(34)
(35)
(36)
(37)
(38)
(39)
(40)
(41)
(42)
Page 173
عدل، احسان
اور
ايتاء ذى القربى
تین بنیادی متخلیقی اصول
خطاب فرموده جلسہ سالانہ اسلام آباد، یو کے 2 اگست 1987ء
حضرت مرزا طاهر احمد
خليفة المسيح الرابع رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى
16- مالی لین دین کی شہادات
17- اللہ تعالیٰ.فرشتوں اور صاحب علم بندوں کی گواہی کا نظام
18- ایک نئی قسم کی شہادت
19 - کائنات میں خدا کا ریکارڈنگ سسٹم
20 - بندہ سے خدا کا معاہدہ اور ذیلی معاہدات
21- غیروں سے معاہدات
Page 175
اسلام میں نظام شہادت
اسلام کا نظام شہادت بہت ہی وسیع مطالب پر پھیلا پڑا ہے اور
جب ہم قرآن مجید اور حضرت اقدس محمد مصطفی ﷺ کے فرمودات
کی روشنی میں اس کی بات کرتے ہیں تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ دنیا کی
عدالت میں جو گواہیاں پیش کی جاتی ہیں اسلامی نظام شہادت بھی
اسی طرح کا ہے.اسلامی نظام شہادت میں حیرت انگیز وسعت :
ہے.اور اس میں عدل کا مضمون بھی ہے، احسان کا مضمون بھی ہے
اور ایتا عذی القربیٰ کا مضمون بھی ہے.اس کی وسعت اور ہمہ
گیری کا یہ عالم ہے کہ خود خدا تعالیٰ نے اپنے آپ کو بھی اس نظام
شہادت کا پابند فرمایا ہے.اسی طرح انبیاء علیہم السلام کو یا بند کرنے
والا بھی ایک شہادت کا نظام پیش کیا ہے.گزرے ہوؤں کے لئے
بھی ایک شہادت کا نظام پیش کیا ہے اور آنے والوں کے متعلق بھی
ایک شہادت کا نظام پیش کیا ہے، مسلمانوں کے غیر مسلمانوں سے
معاملات کے متعلق بھی ایک شہادت کا نظام پیش کیا ہے.ان تمام
جگہوں میں آپ کو عدل، احسان اور ایتا جو ذی القربی کے جلوے
دکھائی دیں گے.
Page 177
مالی لین دین کی شهادت
16- مالی لین دین کی شہادات
165
جہاں تک مالی معاملات کا تعلق ہے چونکہ یہ ذکر پہلے سے جاری ہے اس لئے اسی مضمون کو
آگے بڑھاتے ہوئے کچھ گزارشات پیش ہیں.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:
يَا يُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ
كَمَا عَلَّمَهُ اللهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللهَ
رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهَا
اَوْضَعِيفًا اَوْلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ تُمِل هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ
وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ
فَرَجُلٌ وَامْرَاَتْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ
إحْدهُمَا فَتُذَكَّرَ احْدُهُمَا الْأُخْرى ( البقرة 283:2)
ترجمہ: اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو! جب تم ایک معین مدت تک کے لئے
قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو اور چاہئے کہ تمہارے درمیان لکھنے والا
انصاف سے لکھے.اور کوئی کا تب اس سے انکار نہ کرے کہ وہ لکھے.پس وہ لکھے
جیسا اللہ نے اُسے سکھایا ہے.اور وہ لکھوائے جس کے ذمہ ( دوسرے کا ) حق
ہے، اور اللہ اپنے رب کا تقویٰ اختیار کرے، اور اس میں سے کچھ بھی کم نہ
کرے.پس اگر وہ جس کے ذمہ ( دوسرے کا) حق ہے بیوقوف ہو یا کمزور ہو یا
استطاعت نہ رکھتا ہو کہ وہ لکھوائے تو اُس کا ولی (اس کی نمائندگی میں ) انصاف
سے لکھوائے.اور اپنے مردوں میں سے دو کو گواہ ٹھہرالیا کرو.اور اگر دومرد میسر
نہ ہوں تو ایک مرد اور دوعورتیں (ایسے) گواہوں میں سے جن پر تم راضی ہو.( یہ ) اس لئے ( ہے ) کہ ان دو عورتوں میں سے اگر ایک بھول جائے تو دوسری
اسے یادکروادے.اور جب گواہوں کو بلا یا جائے تو وہ انکار نہ کریں.یہاں جو بات خاص طور پر قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ لین دین کے معاملہ میں لکھنے کی احتیاط اور
Page 178
166
عدل، احسان اور ایتاء ذی القربی - حصه سوم
اسے با قاعدہ اسلامی احکام کی فہرست میں داخل کرنا یہ قرآن کریم کی ایک استثنائی شان ہے.آپ
تمام دنیا کے مذاہب کی الہی کتب کا مطالعہ کر کے دیکھ لیجئے وہاں آپ کو اس مضمون کی کوئی عبارت
دکھائی نہیں دے گی کہ لین دین کے معاملات کو لازماً لکھو.خصوصاً یہ امر پیش نظر رکھنے کے لائق ہے
کہ جس زمانہ میں یہ فرمانِ الہی نازل ہوا اس زمانہ میں جیسا کہ یہ آیت خود گواہ ہے عرب میں لکھنے
پڑھنے کا رواج عام نہیں تھا اور لکھنے کے اہل لوگ کم کم ملتے تھے.لین دین کے معاملات میں ایسی واضح تعلیم حیرت انگیز ہے اور آج جتنے بھی ایسے جھگڑے
مسلمان معاشرہ میں ہیں، ان میں سے بیشتر اس بنا پر پیدا ہوتے ہیں کہ شروع میں دو معاہدہ کرنے
والے زبانی باتوں پر راضی ہو جاتے ہیں جس کے نتیجہ میں شرائط قطعی اور واضح نہیں ہوتیں.حالانکہ
آجکل تقریباً ہر انسان کو لکھنا پڑھنا آتا ہے اور تحریرلکھنا کوئی اچنبھے کی بات نہیں.اسی طرح بسا اوقات
گواہوں کا فقدان ہوتا ہے اور محض تحریر پر اکتفا کیا جاتا ہے جس کے نتیجہ میں قرآن کریم کی ہدایت
میں مضمر گہری حکمت سے فریقین محروم رہ جاتے ہیں.قرآن کریم کا تحریر پر گواہ رکھنے کا مقصد تو یہ ہے
کہ تحریر کے سمجھنے میں اگر کبھی کوئی غلط نہی ہو تو گواہ موجود ہوں اور بتا سکیں کہ دراصل یہ تحریر ان معنوں
میں لکھی گئی تھی اور جس گفتگو کو تحریر میں ڈھالا جارہا تھا اس گفتگو کا یہ مفہوم تھا.اس آیت کریمہ میں اس تفصیل سے اس موضوع کے تمام پہلوؤں پر نظر رکھی گئی ہے کہ تحریر دینا
اس کا ذمہ قرار دیا جس پر حق ہے اور اس میں ایک بہت اہم نکتہ ہے.معاملات میں اگر حق لینے
والے پر تحریر رکھی جاتی تو تحریر کے عمد ابگاڑنے کے نسبتاً زیادہ احتمالات ہوتے.حق دینے والا اگر
اپنے ہاتھ سے یہ تحریر دے دے کہ ہاں میں نے یہ حق دینا ہے تو یہ بہت زیادہ قطعی بات ہے بہ نسبت
اس کے کہ حق لینے والا کوئی تحریر لکھے یا لکھوائے.پھر یہ احتمال بھی موجود ہے کہ جوتحریر دیتا ہے وہ ذہنی طور پر کمزور ہو.اگر اس کی ذہانت کی کمی کی
وجہ سے خطرہ ہو کہ جس حد تک وہ دین دار ہے اس کی بجائے کہیں زیادہ کی ذمہ داری قبول نہ کرلے تو
فرمایا ایسی صورت میں وہ تحریر نہیں لکھوائے گا بلکہ اس کا ولی لکھوائے گا اور پوری احتیاط کرے گا کہ جو
معاہدہ تھا اس کی روح
کو تحریر میں صحیح معنوں میں ڈھالا گیا ہے.اس کا ایک اور پہلو ہے کہ اگر دو مرد میسر نہ آئیں تو ایک مرد اور دو عورتیں گواہی دیں.ایک مرد
اور دوعورتوں کی گواہی سے ہرگز یہ مراد نہیں کہ دونوں عورتیں الگ الگ گواہ کے طور پر پیش ہوں گویا
کل تین گواہ بن گئے.مراد صرف یہ ہے کہ دو عورتوں میں سے ایک گواہ ہو اور دوسری یاد دہانی کے
لئے پاس بیٹھی رہے تا کہ اگر مالی معاملات میں وہ کچھ بھول چکی ہے تو وہ اسے یاد کرا دے.
Page 179
مالی لین دین کی شهادت
پھر فرمایا:
167
وَإِنْ كُنْتُمُ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهُنَّ مَّقْبُوضَةً
ترجمہ: اگر تم سفر پر ہو اور کا تب میسر نہ آئے تو پھر اپنی کوئی چیز رہن با قبضہ کے
طور پر رکھواؤ.فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ
اور جب امانت کسی کے پاس رکھوائی جائے تو جس کے پاس امانت رکھوائی گئی
ہے اس سے جب واپس مانگی جائے تو اس کا فرض ہے کہ تقویٰ کے مطابق اس
امانت کو واپس کرے اور اپنے رب اللہ کا خوف کرے.وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّةَ أَثِمٌ قَلْبُهُ
وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (البقره 284:2)
اور گواہی کو مت چھپاؤ.جو بھی گواہی کو چھپاتا ہے اس کا دل گنہگار ہو جاتا ہے.اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تم کرتے ہو.یہاں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ سفر کے دوران مالی ضرورت پڑنے پر رہن کا مضمون دنیائے
مذاہب میں پہلی بار قرآن کریم نے پیش فرمایا ہے.دیکھا گیا ہے کہ بسا اوقات بعض لوگ اپنے سفر
کے دوران قرض مانگنے کے عادی ہوتے ہیں اور بالعموم لوگ انہیں بیچارے مسافر سمجھ کر کچھ نہ کچھ
قرض دے بھی دیتے ہیں.قرآن کریم نے تو چودہ سو سال پہلے ہی آئندہ زمانے کے تمام انسانوں کے حقوق کی حفاظت کا
اس حد تک خیال رکھا لیکن افسوس ہے کہ فی زمانہ جبکہ اکثر مسافر کچھ نہ کچھ قیمتی چیز بھی ساتھ رکھتے ہیں
جنہیں رہن با قبضہ کے طور پر رکھوانا کچھ مشکل بات نہیں پھر بھی لوگ ان ہدایات کو اہمیت نہ دے کر
اپنا نقصان کرواتے ہیں اور معاشرہ میں تلخی کے بیج بو دیتے ہیں.ایک اور نقصان کا پہلو یہ ہے کہ
معاملات میں بے احتیاطی کا رویہ اختیار کرنے کے نتیجہ میں بددیانتی کو فروغ ملتا ہے.پس ان تفصیلی
ہدایات کو تخفیف کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہئے.مالی امور سے تعلق رکھنے والے یہ دو پہلو چونکہ پہلے زیر بحث نہیں آئے تھے اس لئے ان کے
ذکر کے بعد میں اس مضمون کو ختم کرتا ہوں اور اب شہادت سے تعلق رکھنے والے بعض دیگر امور کی
طرف متوجہ ہوتا ہوں.
Page 180
168
عدل، احسان اور ایتاء ذی القربی - حصه سوم
-17 اللہ تعالیٰ.فرشتوں اور صاحب علم بندوں کی گواہی کا نظام
سب سے پہلے قرآن کریم خدا تعالیٰ کی طرف سے اپنی ہستی کی گواہی پیش فرماتا ہے.خدا ہے
یا نہیں ہے؟ یہ وہ بنیادی فیصلہ ہے جس پر مذہب کی بنیاد ہے.اور اگر خدا ہے تو کس نے دیکھا، اسکی
گواہی کس نے دی؟ سب سے پہلے تو خدا کو خود بولنا چاہئے کہ میں ہوں اور اسکی گواہی پیش کرنی
چاہئے.اس پہلو سے بھی آپ حیران ہوں گے کہ دنیا کی اکثر مذہبی کتب میں خدا کی اپنی گواہی واضح
طور پر موجود نہیں کہ میں ہوں.بعض مذہبی کتب میں موجود ہے لیکن اکثر میں نہیں ہے کہ ایک ہستی
گواہی دے کہ میں ہوں اور پھر اس کے بعد ایک گواہی کا نظام جاری کرے اور وہ ایسا فصیلی نظام ہو
کہ گواہی کے سلسلہ میں کوئی پہلو بھی تشنہ نہ رہے.چنانچہ قرآن کریم فرماتا ہے.شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَئِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَابِمَا بِالْقِسْطِ
لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ( آل عمران 19:3)
66
کہ اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے.”وَالْمَلكَةُ “ اور اس گواہی
میں اس کے فرشتے بھی شریک ہیں." وَ اُولُوا الْعِلْمِ قَابِما بِالْقِسْطِ “ اور صاحب علم (انسان)
بھی اور خدا یہ گواہی انصاف پر قائم ہوتے ہوئے دے رہا ہے.لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ،
اس کے سوا کوئی نہیں جو عبادت کے لائق ہے.وہی ہے جو غالب ہے اور حکمت والا ہے.یا غالب علم
کا مالک ہے.پس اللہ تعالیٰ وہ وجود ہے جو بزرگی والا غالب اور علم و حکمت والا ہے.اس نے یہ
گواہی دی ہے.اب اللہ کی گواہی کو کس نے سنا اور کیسے ہمیں پتہ چلے کہ خدا یہ گواہی دے رہا ہے.اس کے مختلف پہلو ہیں جن سے ہم اس مضمون کو پرکھ سکتے ہیں.سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کی شہادت جو قرآن کریم میں موجود ہے کیا اس کے مقابل
پر
غیر اللہ کی شہادت کسی کتاب میں ملتی ہے کہ جسمیں کسی ایسے وجود نے گواہی دی ہو جسے معبود بنایا گیا
ہے اور یہ کہا ہو کہ اللہ کے سوا میں بھی ایک معبود ہوں.ایسی کوئی گواہی کسی کتاب میں نہیں ملتی.ہاں
انسانوں کے دعوے ضرور ملتے ہیں کہ خدا کے سوا کچھ اور بھی معبود ہیں.پس دنیا بھر میں اللہ کے سوا
دیگر معبود تسلیم کئے جانے والوں کی طرف سے ایسی گواہی کا کلی فقدان ایک حیرت انگیز دلیل اللہ تعالیٰ
کی گواہی کے حق میں ہے.پس جب ایک وجود نے آواز دی کہ میں ہوں اور میرے سوا کوئی نہیں تو
Page 181
الله تعالى فرشتوں اور صاحب علم بندوں کی گواہی کا نظام
169
اسکے سوا اگر کوئی دوسرے معبود بھی ہوتے تو کل عالم میں انکی آواز سے شور بپا ہو جا تا کہ ہم بھی ہیں،
ہم بھی ہیں ، ہم بھی ہیں.مگر ایسا نہیں ہوا.پس مذہب کی دنیا جو خدا کی ہستی کی قائل ہے اس کے لئے مذہب کی دنیا میں خدا کی اس گواہی
کے سوا اور گواہی ہے ہی نہیں جو اسکی تردید کر رہی ہو.جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جو خدا کی ہستی
کے قائل نہیں ہیں ان کے لئے ایک اور طرح کی گواہی بھی قرآن کریم میں پیش کی گئی ہے جسکا میں
بعد میں ذکر کروں گا.ملائکہ کا مضمون جو قرآن کریم میں مختلف جگہ پھیلا پڑا ہے اس کے متعلق جو عارفانہ تشریح
حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے اس تشریح کی رو سے ملائکہ ہر طبعی قوت کے
سردار ہیں اور ان کے تابع دنیا کی تمام طبعی قوتیں جاری و ساری ہیں.ساری کائنات میں جو بھی نظام
ہے جسے سائنس کی دنیا میں آپ فزکس کا نظام کہہ سکتے ہیں یا کیمسٹری کا نظام کہہ سکتے ہیں یا بانی یا
زوالوجی یا دیگر نام ان سائنسوں کے رکھ دیجئے ، جتنا بھی کائنات میں قانونِ قدرت کا نظام جاری
ہے بلکہ ہر نظام کے اوپر ایک فرشتے کا پہرہ ہے جو نگران ہے اور اس کے تابع یہ نظام چل رہا ہے.اس لئے قانونِ قدرت کو جو خود بخود جاری و ساری دیکھتے ہو تو یہ درست نہیں ہے.اس سلسلہ میں
جب آپ ملائکہ کی اس گواہی پر غور کرتے ہیں تو خواہ ملائکہ کے وجود کو تسلیم کریں یا نہ کریں گواہی
بہر حال یہی رہے گی کہ نظام کائنات ایک دوسرے کے ساتھ ایسا ہم آہنگ ہے کہ اگر کوئی اسکا خالق
ہے تو ایک ہی ہے اور صرف ایک ہے.ایک سے زائد خالق و مالک کا تصور کائنات کی گواہی کے
مقابل پر ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے.ساری کائنات زبان حال سے ایک ہی خالق کی طرف اشارہ کر رہی
ہے.دوسری ملائکہ کی گواہی یہ ہے کہ ملائکہ دلوں پر نازل ہوتے ہیں اور دلوں پر نازل ہونے کے بعد
یہ گواہی دیتے ہیں.تمام دنیا میں ملائکہ کے نزول کے متعلق جو بھی تحریرات ملتی ہیں آپ تعجب کریں
گے کہ مشرک مذاہب میں بھی کبھی ملائکہ کی طرف یہ گواہی منسوب نہیں کی گئی کہ وہ نازل ہوئے اور
انہوں نے کہا کہ تم صرف ایک خدا کی پوجانہ کرنا اور بھی کچھ خدا موجود ہیں.66
پھر اُولُوا الْعِلْمِ “ ہیں.قابِما بِالْقِسْطِ “.اگر چہ قابِما بِالْقِسْطِ “ کا موصوف
اللہ تعالیٰ ہے لیکن چونکہ فرشتوں اور صاحب علم لوگوں کو اس گواہی میں شامل کر لیا گیا ہے اسلئے "
قابما “ کا لفظ واحد ہونے کے باوجود ان سب گواہوں پر مضمون کی وحدت کے لحاظ سے چسپاں
Page 182
170
عدل، احسان اور ایتاء ذی القربی - حصه سوم
ہوسکتا ہے.پس اہل انصاف صاحب علم لوگ بھی اس بات کے گواہ ہیں اور ان سے اگر آپ پوچھیں
خواہ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہوں کہ کیا تم نے کبھی ایک خدائے واحد و یگانہ کے سوا کسی
اور خدا سے رابطہ پیدا کیا یا اس نے تم سے رابطہ پیدا کیا.اور کیا تم گواہی دے سکتے ہو کہ خدا کے سوا
کوئی اور تھا جس نے ان سے تعلق جوڑا تو آپ بلا شبہ یہی دیکھیں گے کہ کوئی صاحب علم جو سچ
بولنے اور انصاف پر قائم ہونے کے لحاظ سے نیک شہرت رکھتا ہو ایسی کوئی گواہی پیش نہیں کرے گا.وہ یہ تو کہہ سکتا ہے کہ میرے دل پر کوئی ایک خدا بھی نازل نہیں ہو الیکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایک سے
زائد خدا نازل ہوئے.گو قرآن کریم کے علاوہ بعض دیگر الہی صحیفوں میں بھی خدائے واحد ویگانہ کی یہ
گواہی موجود ہے کہ ایک میں ہی معبود ہوں اور میرے سوا اور کوئی نہیں.لیکن اس مضمون پر جومزید
تفصیلات قرآن کریم نے بیان کی ہیں، دیگر مذاہب انکے بیان سے عاری ہیں.دہریوں کے لئے اللہ تعالیٰ کی ہستی پر گواہی:
قرآن کریم میں ایک آیت میں ایک ایسی دلیل بھی دی گئی ہے جو انسانی فطرت کے طور پر
بیان کی گئی ہے جس کا ذکر سورۃ الاعراف میں یوں کیا گیا ہے:
وَإِذْ اَخَذَرَ بُكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ
وَ اَشْهَدَ هُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا
اَنْ تَقُوْلُوْا يَوْمَ الْقِيِّمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَاغْفِلِينَ (الاعراف 7 : 173)
اور (یاد کرو) جب تیرے رب نے بنی آدم کی صلب سے ان کی نسلوں (کے
مادہ تخلیق ) کو پکڑا اور خود انہیں اپنے نفوس پر گواہ بنادیا ( اور پوچھا ) کہ کیا میں
تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں! ہم گواہی دیتے ہیں.مباداتم
قیامت کے دن یہ کہو کہ ہم تو اس سے یقیناً بے خبر تھے.اس سے مراد یہ ہے کہ بنی آدم کے صلب سے جتنی بھی ذریات نے پیدا ہونا تھا یا ہوئی ہیں یا
آئندہ ہوں گی وہ یہ گواہی ورثہ میں پاتی رہی ہیں یا پائیں گی.اور صلب کے تعلق میں جیسا کہ قرآن کریم
میں مختلف آیات میں یہ بات کھولی گئی ہے صلب کے اندر پیدا ہونے والا وہ مادہ تولید ہے جس کے
اندر انسانی زندگی کا اول سے آخر تک مکمل خاکہ موجود ہے.اور یہ خا کہ اتناتفصیلی ہے کہ انسانی زندگی
کے کسی ادنیٰ سے ادنی عمل کو بھی اس سے آزاد اور باہر قرار نہیں دیا جا سکتا.اور انسانی جسم کا ہر ذرہ
Page 183
الله تعالیٰ فرشتوں اور صاحبِ علم بندوں کی گواہی کا نظام
171
اس خاکے کے مطابق بنایا گیا ہے اور اس کے اندر یہ پنہاں خا کہ ہمیشہ موجود رہتا ہے.اسے سائنسی
اصطلاح میں جینز (Genes) کا نظام کہتے ہیں اور ہر جین (Gene) کے اندر اس کے انسانی
جسم، انسانی دل، انسانی رحجانات، اسکی بیماریوں سے دفاع کی طاقت، اسکی صلاحیتیں ، ہر عمر میں اس
کے اندر پیدا ہونے والی تبدیلیاں اور انکی حدود تمام تر تفاصیل کے ساتھ پہلے سے لکھی ہوئی موجود
ہوتی ہیں.جو چیز وہاں نہ ہو وہ پھر انسان کسی اور ذریعے سے حاصل نہیں کر سکتا.یہ مضمون چونکہ بہت
وسیع ہے یہانتک کہ جیسا کہ میں مضمون کے پہلے حصہ میں ذکر کر چکا ہوں محض ان جینز (Genes)
پر
لکھی ہوئی تحریروں کو ہی پڑھنے میں اور انہیں کتابوں کی صورت میں منضبط کرنے میں سائنسدانوں کو
نسلاً بعد نسل محنت کرنی ہوگی اور جو کچھ معلومات اب تک حاصل ہو چکی ہیں صرف ان کو ہی اگر ضابطہِ
تحریر میں لایا جائے تو سینکڑوں بہت ضخیم کتب لکھی جاسکتی ہیں.پس اول تو قرآن مجید کی اس آیت
سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خدا کے وجود کا تصور کسی ایک زمانے یا کسی ایک نسل کے انسان سے تعلق نہیں
رکھتا بلکہ نسل آدم اس تصور کو ورثہ میں پاتی ہے یہانتک کہ دہر یہ بھی اگر اپنے نفس پر غور کریں تو انکو
اپنے وجود کے اندر ہی خدا کی ہستی کی تحریری گواہیاں دکھائی دیں گی.اسکا یہ مطلب نہیں کہ ہر شخص
شعوری طور پر خدا کا قائل ہوتا ہے.اگر یہ مراد ہوتی تو لفظ علی استعمال کر کے یہ نہ فرمایا جاتا کہ ان
میں سے بہت سے دہریہ ہونگے.اور یہ اندرونی گواہی انکی دہریت کے خلاف کھڑی ہو جائے گی.اس پہلو سے ایک اور آیت کریمہ بھی اسی مضمون پر روشنی ڈالتے ہوئے انسان کی توجہ اس طرف
مبذول فرماتی ہے.سَنُرِيهِمْ أَيْتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ
أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ( حم السجدہ 54:41)
کہ خدا کی ہستی کے دلائل تمام کائنات میں پھیلے پڑے ہیں لیکن اگر کائنات پر
غور کی توفیق نہ ہو تو اپنے دلوں ، اپنی جانوں پر ہی غور کر کے دیکھو تو تمہیں اندر
سے ہی خدا کے وجود اور اس کی وحدانیت کی شہادت ملے گی.لیکن شرط یہ ہے
کہ اسبارہ میں تدبر سے کام لو.یہ کیا تعجب کی بات نہیں کہ دنیا کے ہر خطہ میں خدا کا تصور موجود ہے.خدا کا تصور تو آسٹریلیا
کے Aborigines ہوں یا امریکہ کے Red Indians دونوں میں یکساں موجود
ہے.غرضیکہ نہ تو صرف خدا کی ہستی کا تصور موجود ہے بلکہ خدا کا اپنے بندہ سے انذار یا خوشخبری کی
Page 184
172
عدل، احسان اور ایتاء ذی القربی
- حصه سوم
صورت میں رابطہ کا بھی مستحکم عقیدہ پایا جاتا ہے.ایک اور گواہی جس کا قرآن کریم نے بارہا ذکر فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ ہر صاحب فکر کو یہ لازماً
تسلیم کرنا ہو گا کہ وہ عدم سے وجود میں آیا ہے.اس سے پہلے وہ کچھ بھی نہیں تھا.اور وہ یہ بھی لازماً
تسلیم کریگا کہ میں خود اپنا خالق نہیں ہوں اسلئے ضرور ایک دوسری ہستی کو خالق ماننا پڑے گا.ایک اور دلیل جو انسانی فطرت میں پائی جاتی ہے وہ اس کا بنیادی اخلاقی تصور ہے جو تمام دنیا
کے انسانوں میں یکساں پایا جاتا ہے.سبھی بدی کو بدی اور بھلائی کو بھلائی سمجھتے ہیں.دہریت کے
حامی فلسفی بھی جو خدا کی ہستی کی دوسری دلیل کو ر ڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس دلیل کے مقابل پر
آکر ٹھہر جاتے ہیں کیونکہ انہیں تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ اگر خدا کا کوئی وجود نہیں تو انسانی فطرت میں
morality کا تصور کیوں پایا جاتا ہے.ان کو یہ تسلیم کرنے کے باوجود morality کا انکار کرنا
پڑتا ہے.بصورت دیگر مارکس کے لئے یہ ممکن نہ تھا کہ اشترا کی عمارت کی پہلی بنیادی اینٹ بھی رکھ
سکتا.یا بینٹ مارکس کے اس بنیادی مفروضہ پر بنی تھی کہ انسان ایک اخلاق سے تہی جانور ہے.پس ایک چیز کا اعلیٰ حالت میں پیدا ہونا اور پھر رفتہ رفتہ ٹوٹ پھوٹ اور انہدام کا شکار ہو جانا یہ
ایک طبعی عمل ہے جو ہر پیدا ہونے والی چیز پر جاری وساری ہے.جس سے اسکی پہلی اعلیٰ حالت کی نفی
نہیں ہوتی.قرآن کریم کے نزدیک انسان کی بقا اس کی اخلاقیت پر مبنی ہے.اس تعلق میں وہ کثرت سے
گزری ہوئی قوموں کو شہادت کے طور پر پیش کرتا ہے جو محض اس لئے مٹ گئیں کہ بنیادی اخلاقی
قدروں پر انہوں نے عمل کرنا چھوڑ دیا تھا لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ پیشتر اس کے کہ وہ اپنی
غلطیوں کی پاداش میں مٹادئے جاتے ، اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان میں ایک متنبہ کرنے والا بھجواتا ہے لیکن
پھر بھی جب انہوں نے اس تنبیہ کا انکار کیا تو وہ اپنی ہی پاداشی عمل کے نتیجہ میں مٹادئے گئے.کائنات کی شہادت:
کائنات کی شہادت کی تفصیل بھی قرآن کریم میں موجود ہے جسکا بیج فرشتوں کی اسی گواہی میں
موجود تھا جس کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں.خدا کے واحد ہونے اور شریک کے بغیر ہونے کی جو گواہی
کائنات کے ذرہ ذرہ پر چھاپی گئی ہے اسکی طرف قرآن کریم حسب ذیل آیات میں توجہ دلاتا ہے:
ا مَّنْ خَلَقَ السَّمَوتِ وَالْاَرْضَ وَ أَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَابِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا
Page 185
الله تعالى فرشتوں اور صاحب علم بندوں کی گواہی کا نظام
شَجَرَهَا ءَ إِلهُ مَّعَ اللهِ بَلْ هُمْ قَوْمُ يَعْدِلُونَ آمَنْ جَعَلَ
الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِللَهَا أَنْهُرَا وَ جَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ
الْبَحْرَيْنِ حَاجِزَاء إِلهُ مَّعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ
(النحل 62,61:27)
( یہ بتاؤ کہ ) کون ہے وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لئے
آسمان سے پانی اتارا اور اس کے ذریعہ ہم نے پر رونق باغات لگائے.تمہارے بس میں تو نہ تھا کہ تم ان کے درخت پروان چڑھاتے.(پس) کیا
اللہ کے ساتھ کوئی ( اور معبود ہے؟ ( نہیں نہیں ) بلکہ وہ نا انصافی کرنے والے
لوگ ہیں.173
یا ( پھر ) وہ کون ہے جسنے زمین کو قرار پکڑنے کی جگہ بنایا اور اس کے بیچ میں دریا
جاری کر دیئے اور جس نے اس کے پہاڑ بنائے اور دوسمندروں کے درمیان
ایک روک بنادی.کیا اللہ کے ساتھ کوئی ( اور ) معبود ہے؟ ( نہیں ) بلکہ ان
میں سے اکثر نہیں جانتے.پس قرآن کریم کا یہ فرمانا کہ زمین میں قرار بخشنے کی قوت ہم نے عطا کی ہے، اسے ایسا متوازن
بنادیا کہ اس میں تم قرار پکڑ سکو.کیا خدا کے سوا کوئی اور معبود بھی ہے جو ایسا کرتا ہے.قرار دینے کے
لئے جن حرکات اور موجبات کی ضرورت ہے اگر آپ ان کا مطالعہ کریں تو آپ یہ دیکھ کر حیران
ہونگے کہ سوائے اس کے کہ ڈیزائن کرنے والا یا اسکا مصور ایک ہوز مین قرار کا موجب بن ہی نہیں
سکتی تھی.لاکھوں ایسے محرکات اور وجوہات موجود ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ مناسبت کے نتیجہ
میں زمین کو قرار کا موجب بنائے ہوئے ہیں.اور سائنسدان بھی اسکی کوئی تسلی بخش تو جیہہ پیش نہیں
کر سکتے کہ یہ سارے ایک دوسرے سے ہم آہنگ اتفاقات کیسے اکٹھے ہو گئے؟ کسی ایک پہلو سے
بھی ادنی سا توازن بگاڑ دیں تو زمین قرار کا موجب نہیں رہے گی.قرار کی حفاظت کے لئے جہاں
کہیں بھی عام جاری قوانین میں استثناء کی ضرورتیں پیش آتی رہیں استثنائی قانون بھی رکھ دیا گیا.اسکی بھی بعض معین مثالیں پہلے پیش کی جاچکی ہیں.ایک ادنی سا امر بھی زمین کے کسی مقتدر ڈیزائنر
کے بغیر خود بخود قرار پکڑنے کی طرف اشارہ نہیں کرتا.
Page 186
174
و,
عدل، احسان اور ایتاء ذی القربی - حصه
سوم
وجَعَلَ خِللَهَا أَنْهرًا “ اور اس زمین کے درمیان پانی کے دریا بہا دیے." وجَعَلَ لَهَا
رَوَاسِيَ “ اور اس کے لئے ایسے پہاڑ بنائے جو زمین کو مستحکم کرنے کے لئے اور زندگی کا نظام
مستحکم کرنے کے لئے ضروری ہیں اور جنگا ان انہار سے تعلق ہے جن کا ذکر گزرا ہے.وَ جَعَلَ بَيْنَ
الْبَحْرَيْنِ حَاجِزا اور دو سمندروں کے درمیان روکیں پیدا کیں.” الهُ معَ اللهِ “ کیا
خدا کے سوا کوئی اور معبود ہے جو یہ سارے کام کر رہا ہے.بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ‘ ان میں
اکثر اس سے بے خبر ہیں.یعنی یہ بظاہر الگ الگ تخلیقی مظاہر نہ تو اتفاقاً الگ الگ ہونے والے حادثات سے پیدا ہو سکتے
ہیں، نہ ہی ایک دوسرے سے آزاد مختلف خلق کرنے والی ہستیوں کی تخلیق کہلا سکتے ہیں.اگر ایسا ہوتا تو
ان کے درمیان اندرونی رابطے اور نظم و ضبط اور ایک ہی اعلیٰ مقصد کو پورا کرنے کے لئے ہم آہنگی نہ دکھائی
دیتی.یہ بھی عدل کی ایک عظیم الشان مثال ہے.پانی کو خدا تعالیٰ نے کس طرح رواسی کے ذریعہ ایک
دور کی شکل میں بار بار انسان کی زندگی کے قرار کی خاطر اصل حالت کی طرف لوٹا نا شروع کیا.قرآن کریم نے اس سکیم میں تمام ضروری باتوں کا احاطہ کیا ہے.جب قرآن کریم انسان کی
توجہ اس طرف دلاتا ہے کہ وہ ان باتوں پر غور کرے تو واضح طور پر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ
آنحضرت ﷺ کے زمانہ میں لوگوں کو محض ایک معمولی سا تصور ہوگا کہ یہ سٹم کس طرح کام کرتا
ہے.جب قرآن کریم نازل ہوا تو اس وقت کا انسان یہ بات جانتا تھا کہ پانی سمندروں سے اٹھایا
جاتا ہے.اور پھر بارش کے ذریعہ جو میدانوں اور پہاڑوں پر برستی ہے، واپس سمندر میں چلا جاتا
ہے.تا ہم اس وقت کے لوگوں کو معمولی سا بھی یہ تصور نہ تھا کہ سائنس کے کون سے اصول پانی کو
سمندر سے اوپر اٹھانے اور اسے صاف و شفاف کرنے کے ذمہ دار ہیں.ان کو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ
اس عمل کے دوران ہائی و ولیج بجلی پیدا ہوتی ہے.وہ یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ پانی کے بخارات جو ہوا
میں معلق ہیں ، ان
کو پانی کے قطروں کی شکل میں تبدیل کرنے کے لئے بجلی کی ایک دوسری کی مخالف
قوتوں کی ضرورت ہوتی ہے.
Page 187
ايك نئی قسم کی شهادت
18- ایک نئی قسم کی شہادت
175
اب ہم کلی طور پر ایک نئی قسم کی شہادت کی طرف آتے ہیں جو انسانی فطرت سے تعلق رکھتی
ہے.بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ سب انکار کرنے والے نبی کی گواہی کے خلاف اکٹھے ہو چکے ہیں.لیکن اس کے باوجود قرآن کریم یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ان میں سے ایسے بھی ہیں جن کے دل کی گہرائی
سے یہ حسرت اٹھتی ہے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے.یہ انسانی فطرت کا ایسا راز ہے جو صرف خدائے
عالم اور خبیر ہی جانتا ہے.یقیناً بہت سے مخالفین بھی ایسے ہوتے ہیں جو وقتا فوقتا نبی کی تائید میں ظاہر
ہونے والے نشانات پر غور کرتے ہوئے دل سے چاہتے ہیں کہ کاش وہ بھی مسلمان ہوتے مگر
سوسائٹی کے بندھن انہیں ایسا کرنے کی توفیق نہیں دیتے.چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:
رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ (الحجر 3:15)
کہ بسا اوقات وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، دل سے چاہیں گے کہ کاش وہ
مسلمان ہوتے.انبیاء کی تائید میں ایسے انداری نشانات بھی اترتے ہیں جو منکرین کے گویا دروازے کھٹکھٹاتے
ہیں اور ان پر ہیبت طاری کر دیتے ہیں.اسی مضمون کا ذکر قرآن کریم کے مختلف الفاظ میں ملتا ہے.مثلاً حسب ذیل آیت میں.وَلَا يَزَالُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا تُصِيْبُهُمْ بِمَا صَنَعُوْا قَارِعَةٌ أَوْتَحُلُّ
قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللهِ اِنَّ اللهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ
(الرعد 32:13)
اور وہ لوگ جو کافر ہوئے انہیں ان کی کارگزاریوں کے سبب سے (دلوں کو)
کھٹکھٹانے والی (43) ایک آفت پہنچتی رہے گی یا وہ (تنبیہ) ان کے گھروں کے
قریب نازل ہوگی یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آپہنچے.یقینا اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا.ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ رسول
کریم ﷺ کو مخاطب کر کے فرماتا ہے.لكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَكَةُ يَشْهَدُونَ
وَكَفَى بِاللهِ شَهِيدًا
(النساء 167:4)
Page 188
176
عدل، احسان اور ایتاء ذی القربی - حصه سوم
کہ اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ اس نے جو کچھ تیری طرف اتارا ہے اسے اس
نے اپنے علم کی بناء پر اتارا ہے.اور فرشتے بھی اس کی گواہی دیتے ہیں ، جبکہ
اللہ اکیلا بھی بطور گواہ کافی ہے.فرشتوں کی گواہیاں نظامِ کا ئنات میں رونما ہونے والی وہ گواہیاں ہیں جو فرشتوں کے ذریعہ
ظہور میں آتی ہیں.یہاں لفظ بِعِلمِ نے تحقیق کی ایک کھڑ کی کھول دی ہے.فرمایا أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ ، اسکا
مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ جو کائنات کا خالق ہے اس نے جو قر آن نازل فر مایا وہ اپنے علم پر مبنی قرآن
نازل فرمایا اور خدا کے علم میں جو کائنات کا علم تھا اس میں آنحضرت ﷺ بذات خود شریک نہیں تھے.دنیا کے علم کے لحاظ سے آپ کو امی قرار دینا ایک بہت ہی مناسب اصطلاح تھی.حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم ﷺ کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے جو
کھجور کے نر پودوں
کا بور مادہ پودوں کے بور پر ڈال رہے تھے.اس پر آپ نے فرمایا اگر ایسا نہ بھی
کرو تو بھی پھل اچھا آئے گا.چنانچہ انہوں نے اس سال ایسا نہ کیا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کھجوروں پر
کوئی پھل نہ لگا انہوں نے نبی کریم علیہ سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا اگر تمہارا کوئی دنیوی کام
ہو تو اس کے بارہ میں خود فیصلہ کیا کرو.اور اگر کوئی دینی بات ہو تو اس کے بارہ میں میری طرف
رجوع کرو.(44)
اس واقعہ سے یہ قطعی طور پر ثابت ہو جاتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو دنیاوی سائنس کا اتنا بھی علم
نہیں تھا کہ کھجور کو کس طرح فرٹلائز کیا جاتا ہے.اس کے باوجود قرآن کریم کا بکثرت سائنسی امور
سے پردہ اٹھانا لازماً آپ کا اپنا کلام نہیں بلکہ خدا کا کلام تھا.نبیوں کی شہادت ایک دوسرے کے حق میں :
اللہ کی ذات اور اسکی قدرت اور جبروت اور علم سے متعلق جن گواہیوں کا ذکر گزر چکا ہے وہ
دراصل براہین کی دو دھاری تلوار کا رنگ رکھتی ہیں.ایک طرف وہ دلائل خدا تعالیٰ کی ہستی اور اسکے
وجود، اسکی وحدانیت ، اسکی قدرت اور اس کے علم کامل پر روشنی ڈالنے والی ہیں تو دوسری طرف جس
بندہ پر یہ کلام اتارا جاتا ہے اسکی صداقت پر بھی گواہ ہو جاتی ہیں.کیونکہ اسکی استطاعت سے یہ بات
باہر ہے کہ اتنے عظیم الشان علوم غیبیہ پر بذات خود غلبہ پاسکے.لیکن اس کے علاوہ ایک اور نظام شہادت
Page 189
ايك نئی قسم کی شهادت
177
بھی نبی کی تائید میں جاری کیا جاتا ہے جسکا ذکر حسب ذیل آیت میں ملتا ہے.فرمایا:
وَ مِنْ قَبْلِهِ كِتُبُ مُوسَى اِمَامًا وَ رَحْمَةً وَهَذَا كِتَبُ مُّصَدِّقُ لِسَانًا
عَرَبِيَّا لِيُنْذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ (الاحقاف 13:46)
اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب ایک رہنما اور رحمت کے طور پر تھی.اور یہ ایک
تصدیق کرنے والی کتاب ہے جو فصیح و بلیغ زبان میں ہے تا کہ ان لوگوں کو
ڈرائے جنہوں نے ظلم کیا اور بطورِ خوشخبری ہو ان کے لئے جو احسان کرنے
والے ہیں.اس آیت کا منطوق یہ ہے کہ موسیٰ نے جس وجود کے ظاہر ہونے کی معین خبر دی تھی وہ وجود محمد
رسول اللہ ﷺ کی صورت میں ظاہر ہو گیا.پس جہاں موسیٰ علیہ السلام ، حضرت محمد رسول الله علی
کے مصدق بنے وہاں حضرت محمد رسول اللہ ﷺ اپنی بعثت کے ساتھ موسی کے بھی مصدق ہو گئے.(الاحقاف 11:46)
پھر فرمایا:.قُلْ أَرَعَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ
شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَاءِيْلَ عَلَى مِثْلِهِ فَامَنَ وَاسْتَكْبَرْتُم
إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّلِمِينَ
تو پوچھ کہ کیا تم نے (اس کے نتیجہ پر غور کیا کہ اگر وہ اللہ کی طرف سے ہی ہو
اور تم اس کا انکار کر چکے ہو، حالانکہ بنی اسرائیل میں سے بھی ایک گواہی دینے
والے نے اس کے مثیل کے حق میں گواہی دی تھی پس وہ تو ایمان لے آیا اور تم
نے استکبار کیا.یقیناً اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا.حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ بھی بنی اسرائیل میں ایسے گواہی دینے والے موجود ہیں.فَا مَن وَاسْتَكْبَرُ تُم کہ انہوں نے جب تو رات کا مطالعہ کیا ، ان گواہوں کو دیکھا تو وہ
ایمان لے آئے اور تمہارا یہ حال ہے کہ جب وہ وجود ظاہر ہو چکا ہے تب بھی تم اسکو نہیں پہچان
رہے.وَاسْتَكْبَرْتُم ، در اصل تم تکبر کی وجہ سے منکر ہورہے ہو.اس میں ایک نیا مضمون یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ محض شہادت کافی نہیں ہوا کرتی ،شہادت قبول کرنے
والے میں بھی راستی اور سعادت ہونی چاہیئے.ایک ہی شہادت آپ ایک حج کے سامنے پیش کرتے ہیں وہ
بالکل مطمئن ہو جاتا ہے اور اسے درست اور قطعی تسلیم کر لیتا ہے.وہی شہادت ایک دوسرے حج کے سامنے
Page 190
178
عدل، احسان اور ایتاء ذی القربی - حصه سوم
پیش کرتے ہیں جو ٹیڑھی عقل کا ہو یا بددیانت ہو تو وہ آسمیں کئی قسم کی مین میخ نکالتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ قبول
کرنے کے لائق نہیں.حالانکہ وہ شہادت جھوٹی نہیں ہوتی ، وہ حج جھوٹا ہوتا ہے.پس قرآن کریم یہی مضمون بیان فرما رہا ہے کہ ہم عمداً ایسے لوگوں کو اس لئے بھٹکنے دیتے ہیں کہ وہ
ہیں ہی گندے، جھوٹے اور ظالم.وہ شہادت سے استفادہ کرنے اور ہدایت پانے کے اہل ہی نہیں.دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جس طرح انبیاء کے ماننے والوں کو جس بے رحمی سے مارا کوٹا جاتا ہے
اور جس رنگ میں ان پر مظالم ڈھائے جاتے ہیں کیا کبھی انبیاء اور ان کے ماننے والوں کی طرف
سے بھی ایسا ہی سلوک ان کے مخالفین اور برے اعمال بجالانے والوں کے ساتھ کیا گیا؟ اس سوال کا
جواب ہمیشہ یہی ہوگا نہیں ، ہر گز نہیں“.یہ سلوک ہمیشہ جھوٹوں نے بچوں سے کیا ہے اور کبھی بھی بچوں نے جھوٹوں سے نہیں کیا.یہ
مراد ہے شھود سے کہ وہ اپنے کردار پر خود گواہ بن جاتے ہیں.ایسی بیہودہ حرکتیں کرتے ہیں،
مخالفت کے ایسے ایسے طریق اختیار کرتے ہیں جو اس سے پہلے ہمیشہ جھوٹے سچوں کیخلاف کیا
کرتے تھے.چنانچہ اس کی ایک گواہی پاکستان میں بڑی وضاحت کے ساتھ اس طرح ظاہر ہوئی
کہ کوئٹہ کی عدالت میں جب کلمہ شہادت پڑھنے کے جرم میں مقدمہ چل رہا تھا تو احمدی وکیل نے
وہاں کے جو ملاں بزعم خود ختم نبوت کے سربراہ تھے ، ان سے یہ سوال کیا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو
سلوک کلمہ شہادت سے متعلق آج آپ احمدیوں سے کر رہے ہیں حضرت اقدس محمد مصطفی امیے کے
زمانہ میں یہ سلوک کون کس سے کیا کرتا تھا؟ انہوں نے جواب لکھوایا جو عدالت کی مہر کا تصدیق شدہ
ہمارے پاس موجود ہے کہ میں جانتا ہوں کہ اس زمانہ میں کلمہ پڑھنے والوں سے یعنی حضرت محمد اللہ
اور آپ کے غلاموں سے مشرکین مکہ یہ سلوک کیا کرتے تھے.ایک مسلمہ اصول جس کا اطلاق ایسے تمام معاملات پر ہوتا ہے جہاں شہادت
قبول یارڈ کی جاتی ہے:
سورۃ البقرۃ کی آیت نمبر ۳ بہت جامع آیت ہے جس کا تعلق ایسے تمام حالات سے ہے.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:
ذلِكَ الْكِتَبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ (البقرة 3:2)
یہ ایک کامل کتاب ہے.اس میں کوئی شک نہیں، یہ متقیوں کو ہدایت دینے
والی ہے.
Page 191
ايك نئی قسم کی شهادت
179
مفسرین نے اس کی مختلف تشریحات کی ہیں جو دورانِ تلاوت ایک لفظ پر زور دینے سے تعلق
رکھتی ہیں.اگر چہ کتاب (قرآن کریم میں کوئی شک و شبہ نہیں اور ویسے ہی ہوگا جس کا وعدہ کیا گیا
ہے.لیکن اس میں بھی شک نہیں کہ یہ صرف متقیوں کو ہدایت دے گی.یہ ایک مسلمہ اصول ہے جس کا اطلاق نہ صرف کتب پر ہوتا ہے بلکہ نبیوں پر بھی ہوتا ہے.یہ
اس لحاظ سے بھی آفاقی ہے کہ اس کا اطلاق دنیاوی عدالتوں پر بھی اسی طرح ہوتا ہے.اگر چه قرآنی بیان کے مطابق تمام دنیا کے دیگر بانیان مذاہب نے رسول اللہ ﷺ اور قرآن کے
حق میں پیشگوئیاں ضرور کی تھیں لیکن عملاً یا ان کی پیشگوئیوں کے مصداق کسی اور کو سمجھا گیا یا ان کے
الفاظ ایسے مہم تھے کہ گویا کسی کے آنے کی پیشگوئی تھی ہی نہیں.عملاً قرآن کا ان کی تصدیق کرنا ان
کے کسی احسان کی وجہ سے نہیں تھا جس کا بدلہ اتارا جا رہا ہو.اسکے برعکس دیگر مذاہب نے اگر اسلام
کے حق میں گواہی دی بھی تو ساتھ یہ شرط عائد نہیں کی کہ اگر تم نے اسے قبول نہیں کیا تو تمہارا اس مذہب
سے کوئی تعلق نہیں رہیگا.پس ایک یہودی یا عیسائی اگر محمد رسول اللہ ﷺ کا انکار کرتا ہے تو پھر بھی وہ
یہودی یا عیسائی رہتا ہے مگر یہ ناممکن ہے کہ ایک مسلمان موسیٰ علیہ السلام یا عیسی علیہ السلام کا انکار کر رہا
ہو تو پھر بھی مسلمان رہے.پس اسلام کا شہادت کا یہ نظام ایک نہایت ہی حسین وسعت بھی اپنے اندر رکھتا ہے اور ایک
دلکش تو ازن بھی.عدل کا بھی ایک اعلیٰ درجہ کا نمونہ پیش کرتا ہے اور احسان کا بھی.دیگر تمام مذاہب یا تو ایک دوسرے کے وجودہی سے بے خبر ہیں یا کم سے کم ان کے ذکر سے کلیہ
خالی پڑے ہیں.یا پھر ایسے اصول اپنا چکے ہیں کہ جنکی رو سے ان کے ماننے والے اپنا یہ فرض سمجھتے ہیں
کہ دوسرے مذاہب کے بانیان کو اور انکی مذہبی کتب کو اور ان کے ماننے والوں
کو جھوٹا ما نہیں.آنحضرت ﷺ کے حق میں ماضی کی شہادت کے علاوہ مستقبل کی شہادت:
اب ایک اور شہادت کا مضمون شروع ہو جاتا ہے جو حسب ذیل آیت میں مذکور ہے.فرمایا:
أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيْنَةٍ مِنْ رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدُ مِّنْهُ وَ مِنْ قَبْلِهِ كِتُبُ
مُوسَى اِمَامًا وَ رَحْمَةً ( ہود 18:11)
پس جو کوئی بھی اپنے رب کی طرف سے کھلے کھلے نشان پر ہو اور اس کے پیچھے
اس کا ایک گواہ بھی آنے والا ہو اور ( پھر ) اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب بطور
امام اور رحمت موجود ہو ( تو کیا تم اسے جھٹلا دو گے).
Page 192
180
عدل، احسان اور ایتاء ذی القربی - حصه سوم
اسی مضمون کی دوسری آیات سورۃ البروج کی حسب ذیل آیات ہیں:
وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُوْدِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودِة
قُتِلَ أَصْحَبُ الْأَخْدُودِةُ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودة
وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُوْنَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ (البروج 82:85 )
ترجمہ قسم ہے برجوں والے آسمان کی.اور موعود دن کی.اور ایک گواہی دینے
والے کی اور اس کی جس کی گواہی دی جائے گی.ہلاک کر دیئے جائیں گے
کھائیوں والے.یعنی اس آگ والے جو بہت ایندھن والی ہے.جب وہ اس
کے گرد بیٹھے ہوں گے.اور وہ اس پر گواہ ہوں گے جو وہ مومنوں سے کریں گے.ان متعدد گواہیوں کا مقصد یہ ہے کہ ایک ایسا نبی جس کا زمانہ قیامت تک کے لئے ممتد کر دیا گیا
ہو اور زمانے کے لحاظ سے کبھی بھی اس کا دور ختم نہ ہو اگر اس کے حق میں شھادتیں صرف ماضی سے
تعلق رکھتیں یا اس کی زندگی تک محدود رہتیں تو آئندہ آنے والی دنیا کے لئے ان کی محض ایک تاریخی
حیثیت رہ جاتی.قرآن کریم میں بعد میں آنے والے ایک عظیم الشان گواہ کا ذکر ہونا آپ کے حق میں دی
جانیوالی سابقہ موسوی شہادت کو بھی غیر معمولی تقویت پہنچاتا ہے.یہ محض ایک پیشگوئی نہیں بلکہ اس
آسمانی گواہ کے حق میں جو نا قابل رڈ گواہیاں اس زمانہ کی طرف سے دی جانی تھیں، ان کا بھی ذکر
کر دیا گیا ہے اور وہ گواہیاں پوری ہو کر نہ صرف اس کے حق میں عظیم الشان چمکتے ہوئے نشان بن
گئیں بلکہ اس سے آنحضور کے حق میں اس عظیم گواہ کی اپنی گواہی بھی ایک نا قابل رد شہادت بن
گئی.ضمنا يَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ کے الفاظ میں یہ پیشگوئی بھی موجود تھی کہ وہ اس کا تابع اور اسی کی
امت میں سے ہوگا.تعجب کی بات ہے کہ آج کے مسلمان رسول اللہ علیہ کی اس عظیم الشان فضیلت کو نظر انداز
کر رہے ہیں اور سوچ ہی نہیں رہے کہ وہ شاہد کون ہو گا اور کیسے آئے گا.یاد رکھیں کہ یہاں لازماً ایک
نئے وجود کی طرف اشارہ کیا جارہا ہے جو بعد میں پیدا ہوگا اور وہ اتنا عظیم الشان گواہ ہوگا کہ امت
میں پیدا ہونے والے دیگر صاحب مرتبہ بزرگوں سے اسکا مقام ممتاز اور الگ ہوگا.فرمایا يَتْلُوهُ
شَاهِدٌ منه اسکا ایک معنی یہ ہے کہ ایسا عظیم الشان گواہ ہے کہ جسے خدا اپنی طرف سے بھیجے گا.اس نظام شہادت کی جو قرآن مجید نے پیش فرمایا ہے حدیث بھی بڑی وضاحت سے تائید فرماتی
ا
Page 193
ايك نئی قسم کی شهادت
181
ہے اور بار بار جو آخری زمانہ میں مہدی معہود اور مسیح موعود کے ظہور کی خبریں ملتی ہیں وہ لازماً اسی شاہد
کی طرف اشارہ کر رہی ہیں.پس یہ ایک ایسا عظیم اور پختہ اور ایک دوسرے سے مربوط شہادتوں کا نظام ہے جسکی مثال اس
سے باہر دکھائی دینی مشکل ہے.آنحضرت ﷺ کی صداقت پر اس دور کی ایک ناقابل تردید شہادت جب آپ
نے دعوی کیا:
اب آنحضرت ﷺ اور قرآن مجید کی صداقت پر اس زمانہ کی گواہیوں کا قرآن کریم میں جو ذکر
ملتا ہے وہ پیش کیا جاتا ہے.یعنی اس دور کی گواہیاں جسمیں قرآن نازل ہو رہا تھا اور حضور اکرم ہے
جسم عصری دنیا میں موجود تھے.فرمایا:
قُلْ تَوْشَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرِيكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيْكُمْ
عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُوْنَ
اس پر
(یونس 17:10)
تو کہہ دے اگر اللہ چاہتا تو میں تم پر اس کی تلاوت نہ کرتا اور نہ وہ ( اللہ ) تمہیں
پر مطلع کرتا.پس میں اس ( رسالت ) سے پہلے بھی تمہارے درمیان ایک
لمبی عمر گزار چکا ہوں، تو کیا تم عقل نہیں کرتے ؟
یعنی بچپن سے لے کر جوانی اور جوانی سے لیکر جوانی ڈھلنے تک کا عرصہ یعنی میرے دعوئی سے
پہلے کی زندگی تمام تر اس بات پر گواہ ہے اور تم خود اس دور کے لمحہ لمحہ سے خوب واقف ہو کہ یہ
تمام زندگی ہر قسم کے عیب سے پاک تھی.اور اس تمام عرصہ میں ایک ادنی سا بھی جھوٹ کا شبہ تک کسی
کی طرف سے میرے متعلق عائد نہیں کیا گیا.اور جہاں تک امانت کا تعلق ہے تم ہی لوگ ہو جنہوں
نے مجھے امین کا لقب دے رکھا تھا.پس اس پہلو سے مخاطب کو جو بالخصوص اہل مکہ تھے ایک ایسے
رنگ میں صداقت پر گواہ ٹھہرادیا گیا کہ جس کا انکار ان کے لئے ناممکن تھا.یہاں جونکتہ قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ من قبلم کی شرط بھی لگا دی ہے.یہ نہیں فرمایا کہ میری
ساری زندگی آج بھی تمہارے سامنے گواہ ہے.سب انبیاء کا یہی حال ہے.دعوی کے بعد تو دنیا کا ہر
عیب اسکی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے اور کوئی نبی اس سے مستثنی نہیں.ان کے دعوی سے پہلے اور ان
کے دعوی کے بعد کی زندگی میں ان سے بالکل مختلف سلوک کیا جاتا ہے.وہی جو سب سے زیادہ سچے
Page 194
182
عدل، احسان اور ایتاء ذی القربی - حصه
سوم
کہلاتے تھے ،سب سے زیادہ بڑھ کر جھوٹے کہلانے لگتے ہیں.یہ تو ممکن ہے کہ دشمن نبی کے دعویٰ
کے بعد یہ الزام لگائے کہ تمہاری اپنے دعوی سے پہلے کی زندگی بھی داغدار تھی لیکن دعوئی سے پہلے
دشمن کا اس پر ایسا الزام لگانا ہر گز ثابت نہیں.پس قرآن کریم کی یہ تفریق بہت ہی حکیمانہ تفریق ہے
اور اسمیں ایک ایسی دلیل پیش کی گئی ہے جو بیک وقت کل عالم کے ہر زمانے کے ہر نبی کی صداقت پر
گواہ بن جاتی ہے.دعویٰ سے پہلے تو انبیاء سے قوم کی بہت نیک امیدیں وابستہ ہوتی ہیں.اس شخص
کو جس نے بعد میں نبوت کا دعویٰ کرنا ہو یہ خیال آہی نہیں سکتا کہ میں نے آئندہ جا کر تھیں یا چالیس
سال کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنا ہے اس لئے ابھی سے اپنے نقائص کو چھپا کر رکھوں.اس نوع کی شہادت کو اگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی پر بھی چسپاں کر کے دیکھیں تو
بعینہ وہی نتیجہ سامنے آئے گا جو اس سے پہلے انبیاء کی صداقت پر اس شہادت کا اطلاق کرنے کے نتیجہ
میں نکلتا ہے.حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی کا دعوی تک آپ جائزہ لے کر دیکھ لیں تمام
ہندوستان میں آپ دن بدن زیادہ معروف ہوتے چلے جارہے تھے.قادیان کے قریبی حلقوں میں
ہندؤوں نے آپ کو بڑے غور اور قریب سے دیکھا.آپ کا بچپن دیکھا، آپ کی جوانی دیکھی، جوانی
کو ڈھلتے دیکھا.پھر بڑھاپے کی عمر میں قدم رکھتے ہوئے دیکھا.سکھوں نے بھی دیکھا، دہریوں
نے بھی دیکھا، عیسائیوں نے تبھی دیکھا.ان کے ساتھ تعلق رکھنے والے اور آنے جانے والے غرباء
نے بھی دیکھا اور امراء نے بھی دیکھا.جتنی گواہیاں اس دعوی سے پہلے ملتی ہیں وہ ساری گواہیاں
حیرت انگیز طور پر آپ کی صداقت کی تائید اور اخلاق کی تعریف و توصیف پر مشتمل ہیں.ایک گواہی
بھی نہیں جو اشارہ بھی آپ کی ذات میں موجود کسی بدی کی طرف انگلی اٹھا رہی ہو.یہ گواہیاں تو ملتی
ہیں کہ بچپن سے ہی آپ مسجد کے ہو چکے تھے.غرباء کے ساتھ یہ سلوک تھا کہ جو کھانا گھر سے ملتا تھا
وہ گھر میں کھانے کی بجائے لیکر باہر آجایا کرتے تھے اور غریبوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے.غرضیکہ
آپ کے بچپن اور جوانی کے متعلق جتنی گواہیاں ملتی ہیں اپنوں کی ہوں یا غیروں کی یہی بتاتی ہیں کہ وہ
ایک پاک نفس خدا سے تعلق رکھنے والا پاکباز بچہ تھا.وہ لوگ جو مسلسل اس طرح غرباء کے لئے
قربانیاں کریں، بنی نوع انسان کی خدمت کریں اور کبھی کسی نے ان کے متعلق نازیبا الزام نہ لگایا ہو
اور ان کے سامنے وہ عین جوانی اور ادھیڑ عمر تک پہنچیں جو ہر قسم کے عیوب سے پاک ہو ان پر بلاشبہ یہ
گواہی صادق آتی ہے.فقد لبثت فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون -
Page 195
کائنات میں.خدا کا ریکارڈ نگ سسٹم
19- کائنات میں خدا کا ریکارڈنگ سسٹم
183
اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ انسان کے جو اعمال قیامت کے دن پیش ہونگے ان پر
فرشتوں کی اور خدا کی گواہی کی کیا حیثیت ہوگی.اس پہلو سے بھی آپ دیگر مذاہب کا مطالعہ کریں تو
یہ بات محسوس کئے بغیر نہیں رہ سکیں گے کہ اسلامی تعلیم عدل جن جن شعبوں پر اور جس تفصیل سے
حاوی ہے اس کا پاسنگ بھی ان مذاہب میں موجود نہیں ہے.قرآن کریم یہ نہیں فرماتا کہ تم اس لئے پکڑے جاؤ گے کہ میرے فرشتے گواہی دیں گے کہ تم
بدی کیا کرتے تھے.اگر ایسا کیا جائے تو انسان کہہ سکتا ہے کہ فرشتوں کی مخلوق اور ہے.وہ نہ ہمارے
جذبات سے واقف اور نہ ہمارے اندرونی حالات سے واقف ہیں.چنانچہ واقعہ قریب کے زمانہ
میں ایک اردو شاعر نے یہی اعتراض اٹھا بھی دیا.غالب کہتا ہے.پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق
آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا
که خدایا! تیری گواہی کا نظام عجیب ہے کہ فرشتوں کے لکھے پر ناحق بندوں کو پکڑ رہا ہے.کیا بنی آدم
کا کوئی نمائندہ بھی وہاں بطور گواہ موجود تھا.اللہ تعالیٰ کا غالب کو زبان حال سے یہ جواب ہوگا کہ کسی آدمی کا
تمہارے خلاف پیش ہونا تو درکنار، خودتم ہی اپنے خلاف گواہ پیش ہو گے.چنانچہ قرآن کریم میں ہر انسان
کی جلد کی گواہی، اس کے جسم کی گواہی ، اس کے باطن کی گواہی کا ذکر ہے.یہ ایک بہت گہرا مضمون ہے
جس کی تفصیل میں اس وقت بیان نہیں کرتا.ہاں صرف اتنا کہنا کافی ہے کہ ہر انسان کی اپنی گواہی خدا اور
فرشتوں کی گواہی کی تائید کر رہی ہوگی.چنانچہ قرآن کہتا ہے کہ
فَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مَا فِيهِ وَ يَقُولُونَ يُوَيْلَتَنَا
مَالِ هَذَا الْكِتَبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصُهَا
(الكهف 50:18)
اُس دن مجرم ڈر رہے ہوں گے اور کہیں گے افسوس ہم پر اس کتاب کو کیا ہوا ہے
کہ نہ یہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑتی ہے اور نہ کوئی بڑی چیز مگر اس نے ان سب کو شمار
کر لیا ہے.اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے ہم نے یہ نظام قائم فرما دیا ہے کہ اس کا ئنات میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اس سب کو
Page 196
184
عدل، احسان اور ایتاء ذی القربی - حصه
سوم
ہم ریکارڈ کرتے چلے جارہے ہیں اور جو واقعہ بھی گزر جاتا ہے اس کے گہرے نقش موجودات پر ہمیشہ قائم
رہتے ہیں.تم یہ نہ سمجھو کہ تمہارے اعمال کے آثار مٹتے مٹتے کالعدم ہو جاتے ہیں بلکہ جو کچھ تم کرتے ہواس
کے نقوش تمہارے گردو پیش اور خود تمہاری ذات میں بطور گواہوں کے مرتسم ہوتے چلے جاتے ہیں.چنانچہ حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحت کے طور پر آپ کے الفاظ میں قرآن مجید میں فرمایا:
يُيُنَ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرُدَلٍ فَتَكُنْ فِي
صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَوتِ اَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللهُ إِنَّ اللَّهَ
(لقمان 17:31)
لَطِيفُ خَبِيرٌ
ترجمہ:.اے میرے پیارے بیٹے ! یقیناً اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی
چیز ہو پس وہ کسی چٹان میں ( دبی ہوئی ) ہو یا آسمانوں یاز مین میں کہیں بھی ہو،
اللہ ا سے ضرور لے آئے گا.یقینا اللہ بہت باریک بین (اور ) باخبر ہے.اس سے مراد یہ ہے کہ اس کائنات میں شہادتوں کو منضبط کرنے والا ایسا نظام جاری ہے جس کی
شہادتیں کبھی بھی مٹائی نہیں جاسکتیں.اُس زمانے میں انسان کے تصور یا خواب و خیال میں بھی یہ
بات نہیں آسکتی تھی کہ کوئی ایسا نظام موجود ہے جسے ہم دیکھ نہیں سکتے مگر وہ مسلسل ہر قسم کے رونما ہونے
والے واقعات کو منضبط کرتا چلا جاتا ہے.مگر یہ آیات صاف بتارہی ہیں کہ حضرت اقدس محمد
مصطفی ﷺ کو لازماً ایک عالم الغیب والشہادہ ہستی مطلع فرما رہی ہے.چنانچہ آج اگر آپ کسی
PALANATARIUM میں جا کر دیکھیں کہ اٹھارہ یا بیس بلین سال پہلے کی جو آواز BIG
BANG سے پیدا ہوئی تھی اس کے آثار باقیہ آج تک قائم ہیں اور ان ہی کو بڑھا کر وہ آواز پیدا
کر کے دکھاتے ہیں کہ یہ وہ آواز تھی جو آج سے اٹھارہ یا بیس بلین سال پہلے کے عظیم دھماکے سے
ظہور میں آئی تھی.اور یہ
کبھی بھی کلیتہ نا پید نہیں ہو سکتی.محققین زمین کھودتے ہیں تو لاکھوں کروڑوں
بلکہ اربوں سال پہلے کے آثار ان کو نظر آتے ہیں اور ہر اثر اپنے زمانہ کی ایک روئیداد پیش کرتا ہے گویا
سرگذشت کہانی بیان کر رہا ہے اور وہ کہانی اتنی تفصیل سے
لکھی ہوئی ہے کہ جیسے جیسے انسانی علم ترقی
کرے گا اور بھی باریک در باریک نکات اس پر منکشف ہوتے چلے جائیں گے.کروڑ ہا سال پہلے جو
چیزیں زمین میں مدفون ہوگئی تھیں، وہ جاندار جن کی جنس ہی دنیا سے نا پید ہو چکی ہے انکی ہڈیاں اور
جسموں کے بنیادی خلیے حیرت انگیز طور پر اسطرح محفوظ کر دئیے گئے ہیں کہ آج کا محقق جس جانور کی
لاش کو دیکھتا ہے وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ اس جانور کا حال کیا تھا.اس
کو کیا بیماریاں تھیں اور اس کے اندر کیا
Page 197
کائنات میں.خدا کا ریکارڈنگ سسٹم
185
صلاحیتیں تھیں اور کن صلاحیتوں سے یہ عاری تھا.کتنا تیز دوڑا کرتا تھا.کتنا اس کا قد تھا اور کیا کھاتا
تھا.گوشت خور تھا یا سبزی خور تھا.عام عادات
کیا تھیں بزدل تھا یا بہادر تھا.بے وقوف تھا یا عقل والا
تھا.گویا ان گنت سال پہلے روئے زمین پر بسنے والے ہر قسم کے جانوروں کے روز مرہ کی حرکات و
سکنات اور طرز بود و باش کے نقوش ایک واضح تصویر کی صورت میں ابھرتے چلے آتے ہیں.اسی
طرح مثلاً ایک پرانے ڈھانچے کا سائنسی تجزیہ کرنے سے خواہ وہ جانوروں کا نہیں بلکہ کسی قدیم
انسان کا ہو، وہ پورے وثوق سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس شخص کا وہ ڈھانچہ تھا وہ مسفلس یعنی آتشک کی
بیماری میں مبتلا ہو کر مرا ہے.غرضیکہ ہر تحریر محفوظ ہے اور ہر تحریر بول رہی ہے.انسان اپنی کم علمی کے
باوجوداگر خدا کے اس ریکارڈ کو پڑھ رہا ہے تو کتنا بے وقوف ہوگا اگر وہ اپنے آپ کو خدا سے محفوظ سمجھے
اور یہ گمان کرے کہ اس کے تمام اعمال ماضی میں دفن ہو چکے ہیں اور کبھی اسے مجرم ثابت کرنے کے
لئے اس کے سامنے انکی شہادتیں پیش نہیں کی جاسکیں گی.وہ جس نے سب کچھ پیدا کیا وہ اس نظام
کی مخفی تحریرات کو آجکل کے آرکیالوجسٹس (Archaeologists) کی نسبت بہت بہتر سمجھ سکتا
ہے.اگر انسان باریکی سے اس سارے نظام کا مطالعہ کرے تو اتنا خوف زدہ ہو جائے کہ اسکا جینا
حرام ہو جائے.ہم مخفی سے مخفی آواز جو اس کے دل میں پیدا ہوئی اور ابھی الفاظ میں نہیں ڈھلی اسکو
ریکارڈ کرنے کا نظام بھی موجود ہے.انسان جواب طلبی کے دن سے کیسے بچ سکے گا!.چنانچہ آنحضرت ﷺ اس نظام کا ذکر کرتے ہوئے کہ ہر چیز دوبارہ اکٹھی کی جائے گی اور گواہ
کے طور پر پیش کی جائے گی اس کے ساتھ ایک اور مضمون کو شامل کر دیتے ہیں اور وہ مغفرت کا مضمون
ہے.آنحضرت ﷺ نے ایک تمثیل بیان فرمائی کہ ایک شخص بڑا ہی گنہ گار تھا.اتنا گنہ گار تھا کہ گناہ کی
جتنی بھی قسمیں ہیں، جن تک بھی اسکی رسائی تھی وہ سارے گناہ کر لئے اور اپنی ہر حسرت پوری کر لی
اور جب مرنے کے قریب آیا تو اسے کامل یقین تھا کہ چونکہ اس سے زیادہ بڑھ کر گنہگار کوئی نہیں ہو
سکتا اسلئے لازم وہ تو جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا.چنانچہ اس نے اپنے بچوں
کو اکٹھا کیا اور نصیحت کی
کہ جب میں مرجاؤں گا تو تم مجھے جلا کر خاکستر کر دینا پھر اس راکھ کو ہواؤں میں اڑا دینا اور پانیوں پر
بکھیر دینا یہانتک کہ وہ زمین پر ، ہواؤں میں اور پانیوں میں بکھر کر ہمیشہ کے لئے نابود ہو جائے.یہ
نصیحت کر کے وہ مر گیا اور اسکی اولاد نے ایسا ہی کیا.آنحضرت ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی کہ
قیامت کے دن خدا ہوا کو یہ حکم دے گا کہ اس شخص کے ان تمام ذرات کو جن کو تو اڑائے لئے پھرتی
تھی اکٹھا کر اور خشکیوں کو حکم دے گا کہ جہاں جہاں وہ ذرے ہیں ان کو یکجا کرو اور پانیوں کو حکم دے گا
Page 198
186
عدل، احسان اور ایتاء ذی القربی - حصه سوم
کہ ان ذروں کو دوبارہ اگل دو جوان میں ڈوب گئے تھے اور ان کو اکٹھا کر کے دوبارہ وہی وجود پیدا
فرمادے گا اور پھر اس سے پوچھے گا کہ تم نے کیوں ایسا کیا تھا.کیا تم مجھ سے بھاگنا چاہتے تھے؟ ( یاد
رہے کہ رسول اللہ کے یہ الفاظ تمثیل کے طور پر ہیں.اس
کو ظاہر پر محمول کرنا کم نہی ہوگی.مراد صرف
یہ ہے کہ انسان کی کچھ پیش نہیں جاسکتی اس نے جو کچھ کہا وہ انمٹ تحریروں کے طور پر ہمیشہ محفوظ رہے
گا.) تو وہ جواب دے گا کہ اے خدا! میں تجھ سے بہت ڈرتا تھا.میرے دل میں ان گناہوں کے باوجود
تیری خشیت ضرور تھی.پس میں نے تیرے خوف کی وجہ سے تیری عقوبت سے بچنے کے لئے یہ ترکیب
سوچی.تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جو مجھ سے ڈرتا رہتا ہے میں اسکو معاف بھی کر سکتا ہوں.چنانچہ سب
سے بڑے گناہ گار کو اس پر کامل مقدرت حاصل کرنے کے بعد خدا تعالیٰ معاف فرما دے گا.(45)
یہ گناہوں پر جرات دلانے والا مضمون نہیں بلکہ خوف کی حالت میں لرزاں ہونے والوں کے
لئے اس میں نجات
کا پیغام ہے کہ ایسا ممکن ہے کہ تمہارے دل کی کوئی نیک کیفیت، کوئی پاک ارادہ
خدا کے ہاں مقبول ہو جائے.اس لئے اسکی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو.لیکن یہ نہ سمجھنا کہ تم خدا کو
دھوکہ دے لو گے یا اس سے کوئی چیز چھپا لو گے.لوگوں میں عام طور پر باوجود اسکے کہ جانتے ہیں کہ
خدا کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا لاشعوری طور پر ایسی حرکتیں سرزد ہوتی رہتی ہیں جو عملاً خدا کو دھوکہ دینے
کے مترادف ہوتی ہیں.بچوں میں بھی یہ بات دکھائی دیتی ہے.مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا ایک دفعہ میں
نے ایک چھوٹے لڑکے کو بڑی تیزی کے ساتھ نماز پڑھتے دیکھا.وہ اس قدر تیزی سے ٹکریں مار رہا
تھا کہ اس تیز رفتاری کے ساتھ قیام، رکوع اور سجود میں کچھ پڑھا جاہی نہیں سکتا.مثلاً سجدے میں تین
وقعه سبحان ربی الاعلی پڑھنا ہو تو اسکے لئے کچھ تو وقت چاہیئے.تو میں نے بڑے پیار سے
اسکو سمجھایا کہ دیکھو اس تیز رفتاری کے ساتھ پڑھنے سے کچھ بھی فائدہ نہیں کیونکہ یہ مضمون سے خالی
نماز ہے.اس نے کہا کہ اللہ میاں ٹوں ٹرخار ہیاواں پڑھنا کتنے ائے یعنی پڑھنا تو میری نیت ہی
نہیں ہے.میں تو ادا ئیگی فرض کر کے اللہ تعالیٰ کوٹر خا رہا ہوں.ٹرخانے کا بعینہ صحیح ترجمہ تو مشکل ہے
مگر مراد اسکی یہ تھی کہ ظاہری طور پر فرض پورا کر کے اپنے سر سے یہ بوجھ اتار رہا ہوں.وہ تو ایک جاہل
بچہ تھا لیکن واقعتہ بعض بڑے بڑے عالم، بڑے قابل لوگ جو مذہب کی باریکیوں سے بھی واقف
ہیں اپنی ساری زندگی اسی قسم کے مکر و فریب میں ضائع کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ خدا کا حساب
بے باق کر دیا.خدا تعالیٰ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا جیسا کہ مندرجہ ذیل آیات ظاہر کرتی ہیں:
661
شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
Page 199
کائنات میں.خدا کا ریکارڈ نگ سسٹم
وَقَالُوْا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا انْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِى
انْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ )
وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ
وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرً ا مِمَّا تَعْمَلُوْنَ
( حم السجدہ 21:41 تا 23)....ان کے کان اور اُن کی آنکھیں اور اُن کے چمڑے اُن کے خلاف گوہی
دیں گے کہ وہ کیسے کیسے عمل کیا کرتے تھے اور وہ اپنے چمڑوں سے
کہیں گے تم
نے کیوں ہمارے خلاف گواہی دی؟ وہ جواب دیں گے کہ اللہ نے ہمیں بلوایا
جس نے ہر چیز کو گویائی بخشی ہے اور وہی ہے جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا
اور اُسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے.اور تم (اس سے ) چُھپ نہیں سکتے تھے کہ
تمہارے خلاف تمہاری سماعت گواہی دے اور نہ تمہاری نظریں ( گواہی دیں)
اور نہ تمہاری جلدیں.لیکن تم یہ گمان کر بیٹھے تھے کہ اللہ کو تمہارے بہت سے
187
اعمال کا علم ہی نہیں.یہ ایسی ہی کیفیت ہے جیسے کبوتر خطرہ سے بچنے کے لئے اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے اور سمجھتا ہے
کہ وہ دکھائی نہیں دے رہا.یا پھر شتر مرغ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ ریت میں اپنا سر دھنسا کر یہ
سمجھتا ہے کہ وہ ہر دیکھنے والے کی نظر سے غائب ہو گیا ہے.وہ لوگ جو اس غلط فہمی میں زندگی بسر کر
دیتے ہیں کہ وہ دنیا ہی کی نظر سے نہیں خدا کی نظر سے بھی چھپے بیٹھے ہیں ان کے سامنے جب یہ نظام
شھادت حشر کے دن پیش کیا جائے گا تو ان پر خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ فرد جرم بدرجہ کمال درست
ثابت ہوگی کہ وَلكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ.
Page 200
188
عدل، احسان اور ایتاء ذی القربی - حصه سوم
20.بندہ سے خدا کا معاہدہ اور ذیلی معاہدات
اب معاہدات کی بات کرتے ہیں.جہاں تک معاہدات کا تعلق ہے اس مضمون کو بھی خدا تعالیٰ نے
بڑی وضاحت اور وسعت کے ساتھ روشن فرما دیا ہے.قرآن کریم کی آیات میں ایک ایسی عظیم الشان
ترتیب ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے اور نہایت حسین پیرائے میں باہم منسلک اور
مربوط ہے.فرمایا:
اِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ۚ فَمَنْ
نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُتُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْ فِى بِمَا عُهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ
فَسَيُؤْتِيْهِ أَجْرًا عَظِيمًا
(فتح 11:48)
یقیناً وہ لوگ جو تیری بیعت کرتے ہیں وہ اللہ ہی کی بیعت کرتے ہیں.اللہ کا
ہاتھ ہے جو ان کے ہاتھ پر ہے.پس جو کوئی عہد توڑے تو وہ اپنے ہی مفاد کے
خلاف عہد توڑتا ہے اور جو اُس عہد کو پورا کرے جو اس نے اللہ سے باندھا تو
یقیناً وہ اسے بہت بڑا اجر عطا کرے گا.اس میں پہلی قابل غور بات تو یہ ہے کہ جسے ہم بیعت کہتے ہیں کیا ایک انسان کو خدا کے نام پر
کوئی معاہدہ کرنے کا حق ہے یا نہیں.کیونکہ جس کے ساتھ معاہدہ کیا جاتا ہے اسکا صاحب اختیار ہونا
لازمی ہے.بغیر صاحب اختیار ہونے کے کوئی کیسے معاہدہ کر سکتا ہے.چنانچہ قرآن کریم کا آپ
مطالعہ کریں تو اوّل سے آخر تک انبیاء کے صاحب اختیار ہونے کا مضمون پہلے چھیڑا ہے اور یہ فرمایا
ہے کہ جب تم انبیاء کی بیعت کرتے ہو، انکو تسلیم کرتے ہو تو اس لئے نہیں کہ ان کو اپنی ذات میں حق
ہے کہ تم سے کوئی معاہدہ کریں.کسی فرد بشر کو کوئی حق نہیں ہے کہ خدا کے نام پر کوئی معاہدہ کرے یہ حق
صرف خدا کو ہے.اسلئے جب وہ کسی کو مقرر فرماتا ہے تو اسکی بیعت کرنا بظاہر ایک بندہ کی بیعت کرنا
دکھائی دیتا ہے لیکن دراصل بیعت کرنے والا خدا کی بیعت کر رہا ہوتا ہے.کیونکہ اگر وہ خدا کی بیعت
نہیں ہے تو وہ شرک ہے پس اس آیت کے مضمون کو نہ سمجھنے کے نتیجہ میں بعض لوگوں نے اسپر شرک کی
تعلیم کا الزام لگا دیا ہے حالانکہ یہ شرک کی کلی تا نفی کرنے والی آیت ہے.چنانچہ بہائی اس آیت پر اعتراض کرتے ہیں اور خود مجھے بھی ایک دفعہ ایک مجلس میں اس
Page 201
بندہ سے خدا کا معاہدہ اور ذیلی معاهدات
189
اعتراض کا جواب دینے کی توفیق عطا ہوئی.ایک بہائی نے اٹھ کر مجھے چیلنج کیا کہ تم کہتے ہو کہ
قرآن کریم توحید کامل کو پیش کرتا ہے میں اسکا نقص بتا تا ہوں.دیکھو قرآن میں لکھا ہے"
إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللهَ “ کہ اے
محمد! جو تیری بیعت کر رہے ہیں وہ اللہ کی
بیعت کر رہے ہیں.یعنی تو اللہ ہے.اس نے کہا کہ دیکھو جو وہم تھا کہ یہ مجازی کلام ہے اسے آگے
چل کر دور کر دیا اور یہ کہہ دیا یدُ اللهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ “ کہ یہ لوگ جو محمد کی بیعت کر رہے ہیں ان
پر محمد کا نہیں بلکہ اللہ کا ہاتھ ہے.حالانکہ وہ ہاتھ محمد مصطفی ﷺ کا ہی ہاتھ تھا.تو اسکو پھر میں نے
تفصیل سے مضمون سمجھایا اور امید رکھتا ہوں کہ اسے سمجھ آ گئی ہوگی.لیکن اردگرد کے جو دوسرے لوگ
تھے ان کو یقینا سمجھ آ گئی تھی کہ یہ شرک کے خلاف تعلیم دینے والی آیت ہے، شرک کی طرف مائل
کرنے والی نہیں.کیونکہ اگر کوئی انسان خدا کے نام پر کسی ایسے بندہ سے عہد کر لیتا ہے جسے خدا نے
مقرر نہیں فرمایا تو اس نے گویا ایک خدا گھڑ لیا.اس مضمون کو بڑی لطافت سے دیگر انبیاء کے متعلق بھی خدا تعالیٰ نے بیان فرمایا.چنانچہ سب
سے پہلا نبی جسے قرآن کریم پیش کرتا ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں جن سے سلسلہ نبوت اور
سلسلہ بیعت کا آغاز ہوا.سب سے پہلے یہ سوال اس موقعہ پر اٹھا کہ اگر آدم کی اطاعت کی جائے تو
کیوں کی جائے جبکہ وہ انسانوں میں سے ایک انسان تھا.قرآن کریم اسکا جواب یہ دیتا ہے کہ آدم کو
في ذات یہ حق نہیں کہ وہ کسی دوسرے بندہ کی گردن اپنے سامنے جھکائے بلکہ اسے یہ حق اس وقت
حاصل ہوتا ہے جب خدا تعالیٰ اس سے کلام فرمائے اور اسے مامور کر دے.پس آدم کی اطاعت
دراصل فی نفسہ آدم کی اطاعت نہیں بلکہ امر اللہ کی اطاعت ہے.اگر یہ نہ ہو تو پھر آدم کی اطاعت کسی
پر فرض نہیں رہتی.اس وضاحت کے بعد اگر ان آیات کا مطالعہ کریں جن میں آدم کو سجدہ کرنے کا ذکر ملتا ہے تو
ان کے منطوق اور مفہوم کو آپ زیادہ آسانی اور صراحت سے
سمجھ سکیں گے.چنانچہ فرمایا:
إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ
وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَجِدِينَ (ص 38 : 72-73)
جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں گیلی مٹی سے ایک بشر پیدا کرنے
والا ہوں.پس جب میں اسے مکمل کرلوں اور اس میں اپنا کلام ڈال دوں تو تم
لوگ فرمانبرداری کے ساتھ اس کے آگے جھک جاؤ.
Page 202
190
عدل، احسان اور ایتاء ذی القربی
- حصه سوم
سَوَّيْتُه “ کے بیان میں زندگی کے پیدائش کے آغاز سے لیکر جو کچھ مٹی سے ہوا.ارتقاء کی
وہ ساری منازل بیان ہو گئیں جن سے گزرتا ہوا انسان بالآخر شجر تخلیق کے سب سے آخری پھل کی
صورت میں ظاہر ہوا.غور طلب بات یہ ہے کہ اس کے باوجود کہ اسکا تسویہ ہو گیا اور ہر پہلو سے وہ
ٹھیک ٹھاک بنادیا گیا یہ نہیں فرمایا کہ باقی سب زندہ وجود اسکی اطاعت میں جھک جائیں بلکہ ایک
شرط عائد فرمائی کہ جب میں اس میں اپنی روح پھونکوں تب اسکی اطاعت تم پر فرض ہوگی.روح کا لفظ بہت سے معانی پر اطلاق پاتا ہے.عام طور پر سابقہ بہت سے مسلمان علماء یہ
مطلب سمجھتے رہے کہ اس سے مراد زندگی ہے اور تخلیق کا نقشہ ان کے ذہن میں یہ ابھرا کہ خدا تعالیٰ
نے مٹی سے ایک مادھو بنایا پھر اس کے نوک پلک درست کئے جس طرح ایک بت گرمٹی کا بت بناتا
ہے اور پھر کہیں اس کے نقش ابھارتا ہے، کہیں بعض حصوں کو دباتا ہے، کہیں خم پیدا کرتا ہے.غرضیکہ
بڑی محنت سے اور توجہ سے رفتہ رفتہ اس کے نوک پلک درست کر کے اسے ایک خوبصورت انسانی پیکر
میں تبدیل کر دیتا ہے اسی طرح خدا تعالیٰ نے عمل فرمایا.پس ٹھیک ٹھاک کرنے کے عمل تک وہ محض
بت کا بت تھا اور اسمیں زندگی کی کوئی رمق پیدا نہیں ہوئی تھی.پھر جب یہ فرمایا کہ وَنَفَخْتُ فِيْهِ
مِنْ رُّوحِی “ تو مراد یہ ہے کہ آسمیں زندگی پھونکی.افسوس کہ اس تمسخر آمیز تخلیق آدم کا تصور
باندھنے سے پہلے انہوں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ کہیں ایک جگہ بھی خدا تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا
کہ پھر میں نے اسے زندہ کر دیا.حالانکہ اگر " نَفَخْتُ فِیهِ مِنْ رُوحِی “ سے مراد زندگی عطا
کرنا ہوتا تو کسی ایک جگہ تو خدا تعالیٰ نے سیدھے سادھے لفظوں میں ذکر فرما دیا ہوتا مثلاً فــلــمــا
احبيته “ کہا جا سکتا تھا.کہ جب میں اسے زندہ کر دوں.مزید برآں ایسے علماء کو اس بات پر بھی غور
کرنا چاہیئے تھا کہ اپنی روح پھونکنے کا ذکر ہے.کیا نعوذ بالله من ذلک خدا نے اپنی زندگی میں
سے کچھ حصہ آدم کے جسم میں داخل فرمایا تھا.پھر روح کا کیا معنی ہے.قرآن کریم اس مسئلہ کو یوں
حل فرماتا ہے:
وَيَسْلُوْنَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي
( بنی اسرائیل 86:17)
اور وہ تجھ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں.تو کہہ دے کہ روح میرے
رب کے حکم سے ہے.یعنی روح سے مراد اللہ کا امر ہے.اور بائبل کے محاورہ میں لفظ کلام بھی اسی امر کی طرف اشارہ
کرتا ہو ا معلوم ہوتا ہے.حضرت عیسی علیہ السلام کو جو Word of God کہا جاتا ہے اسکا
مطلب یہ ہے کہ وہ خدا کے امر سے پیدا ہوئے ہیں.
Page 203
بندہ سے
النت
خدا کا معاہدہ اور ذیلی معاهدات
ميثاق النبيين :
191
جہاں تک انبیاء کی ذات کا تعلق ہے وہ عہد لینے کے مجاز بنائے جانے سے پہلے خود اللہ تعالیٰ
کے ساتھ ایک ایسے عہد کے رشتے میں باندھے جاتے ہیں جو عام انسانوں کے عہد سے بالا تر ہے
اور در حقیقت اس عہد سے ہی وہ زمین میں خلیفتہ اللہ ہونے کے مجاز ٹھہرتے ہیں یعنی اس عہد کے
بعد ان کے لئے خدا کی رضامندی کے سوا کوئی اور بات کہنا ناممکن ہو جاتا ہے.روز مرہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک منصف جب لوگوں سے سچائی پر قائم رہنے کا حلفیہ بیان لیتا ہے تو
وہ خود بھی جب اسے منصف بنایا جاتا ہے تو حکومت کے بالا نمائندوں کے سامنے اسی کا ایک حلف
اٹھاتا ہے.چنانچہ اس مضمون کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا:
وَإِذْ اَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّنَ مِيْثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَهِيمَ
وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْطَانُ لِيَسْتَلَ
الصُّدِقِيْنَ عَنْ صِدْقِهِمْ ۚ وَأَعَدَّ لِلْكَفِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًاO
(احزاب 8:33-9)
اور جب ہم نے نبیوں سے ان کا عہد لیا اور تجھ سے بھی اور نوح سے اور ابراہیم
اور موسیٰ اور عیسی ابن مریم سے.اور ہم نے ان سے بہت پختہ عہد لیا تھا تا کہ وہ
سچوں سے ان کی سچائی کے متعلق سوال کرے.اور کافروں کے لئے اس نے
دردناک عذاب تیار کیا ہے.نبیوں سے لئے گئے اس عہد کی تفصیل تو یہاں نہیں بتائی گئی لیکن اسکا مقصد بیان فرما دیا
لِيَسْتَلَ الصَّدِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ “ چونکہ انبیاء کو غیروں سے عہد لینے کی نمائندگی عطا کی گئی
ہے اسلئے انہیں بھی تو صدق پر کار بند رہنے کے لئے کسی عہد کا پابند ہونا پڑے گا اور یہ وہی عہد ہے
جسکا ابھی ذکر گزرا ہے.پس عہد کے نتیجہ میں ہم سب کی گردنیں خدا کے حضور جھکائی جاتی ہیں اور
اس عہد کی رو سے ہم سے جواب طلبی کی جاتی ہے.اسی لئے فرمایا کہ ہر قوم کے لئے اسکی کتاب اس
پر گواہ بنے گی کیونکہ دراصل وہی عہد ہے اور یہ نہیں ہوگا کہ ایک امت کے انسانوں کو کسی دوسری
امت کے پیغام کے ساتھ پر کھا جائے اور اس کے مقابل پر ان سے مطالبہ کیا جائے کہ اپنے اعمال کو
اس کتاب یا عہد کے مطابق سچا کر کے دکھاؤ.فرمایا:
كُل أُمَّةٍ تُدْعَى إلى كتبها (الجاثية 29:45)
ترجمه....ہر امت اپنی کتاب کی طرف بلائی جائے گی.
Page 204
192
عدل، احسان اور ایتاء ذی القربی - حصه سوم
ہرامت اپنی کتاب کی طرف بلائی جائے گی اور اس عہد کے مطابق جو اسکی کتاب میں درج ہے
قیامت کے دن اس سے سوال کیا جائے گا.خدا تعالیٰ کی عجیب شان ہے کہ اس نے ایک عہد تو انبیاء
سے اپنے تعلق میں لیا تا کہ وہ اس عہد کی رو سے خدا تعالیٰ کے سامنے جوابدہ ٹھہر ہیں.اور ایک عہد انبیاء
کا ان کی امتوں سے تعلق کے سلسلہ میں لیا تا کہ ان کی امتیں اس عہد کی رو سے انبیاء کے سامنے جوابدہ
ٹھہریں.لیکن ایک تیسرا عہد بھی لیا جسکا ذکر دوسرے کسی مذہب میں وضاحت کے ساتھ نہیں ملتا اور وہ
عہد ہے انبیاء کے انبیاء سے تعلقات کا عہد اور انبیاء کی امتوں کے بعد میں آنے والے دوسرے انبیاء
کے ساتھ تعلق کا عہد.غرضیکہ یہ عہد کا سلسلہ ایک مکمل دائرہ اختیار کر لیتا ہے.فرمایا:
وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيْثَاقَ النَّبِيِّنَ لَمَا أَتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَبٍ وَ حِكْمَةٍ ثُمَّ
جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مُصَدِّقُ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ
قَالَ ءَ اَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ اِصْرِفْ قَالُوا اَقْرَرْنَا
قَالَ فَاشْهَدُوْا وَأَنَا مَعَكُمْ مِّنَ القَهِدِينَ ( آل عمران 82:3 )
اور جب اللہ نے نبیوں کا میثاق لیا کہ جبکہ میں تمہیں کتاب اور حکمت دے چکا
ہوں پھر اگر کوئی ایسا رسول تمہارے پاس آئے جو اس بات کی تصدیق کرنے
والا ہو جو تمہارے پاس ہے تو تم ضرور اس پر ایمان لے آؤ گے اور ضرور اس کی
مدد کرو گے.کہا کیا تم اقرار کرتے ہو اور اس بات پر مجھ سے عہد باندھتے ہو؟
انہوں نے کہا (ہاں) ہم اقرار کرتے ہیں.اس نے کہا پس تم گواہی دو اور
میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں.یہاں کتاب سے مراد تو ظاہر ہے وہ آیات الہی ہیں جو نبی پر نازل ہوتی ہیں.ان میں اوامر بھی
ہوتے ہیں اور نواہی بھی.اس وحی کو کتاب کہا جاتا ہے اور حکمت اس کتاب میں مضمر وہ فلسفہ ہوتا
ہے جو نبی پر ظاہر فرمایا جاتا ہے اور وہ اپنی امت کو اس کے مطابق تعلیم دیتا ہے.چنانچہ قرآن کریم
نے آنحضرت ﷺ کے دونوں کام بیان فرمائے.فرمایا:
يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَب وَالْحِكْمَةَ الجمعة 3:62)
وہ کتاب کی ظاہری تعلیم بھی دیتا ہے اور اسکا فلسفہ، اس کے پوشیدہ راز بھی ان کو
سمجھاتا ہے.
Page 205
بندہ سے خدا کا معاہدہ اور ذیلی معاهدات
193
اسی طرح ایسے غیر شرعی انبیاء جو بعد میں مبعوث ہوتے ہیں اور نئی کتاب نہیں لاتے وہ بھی کسی
پہلے نبی کی کتاب کی پیروی کرتے ہیں اور ضرورت زمانہ کے لحاظ سے اس کی مزید حکمتیں بیان
کرتے ہیں.تو فرمایا جب خدا نے نبیوں سے ایک عہد لیا وہ نبیوں والا عہد یہ تھا کہ جب بھی تمہارے
پاس کتاب آئے اور حکمت بھی بیان ہو چکی ہو اور تم یہ مجھ بیٹھے ہو کہ سب کچھ مکمل ہو گیا، کتاب بھی مل
گئی حکمتیں بھی بیان ہو گئیں گویا اب کوئی ضرورت باقی نہیں رہی ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ “ پھر
تمہارے پاس کوئی پیغمبر آئے تو اگر وہ تمہاری مسلمہ کتاب اور اس کتاب کی بیان فرمودہ حکمتوں کی
تصدیق کرتا ہو اور ان سے انحراف کرنے والا نہ ہو.یہ میثاق اسبين جو سورۃ آل عمران میں تفصیلاً مذکور ہے اسی میثاق النبیین کے متعلق سورة
الاحزاب کی متعلقہ آیت کھلے کھلے لفظوں میں یہ بیان کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آنحضرت ﷺ کو
مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ یہ نبیوں کا عہد تجھ سے بھی لیا ہے وَ مِنْكَ ضمناً یہاں یہ سوال
اٹھتا ہے کہ اگر رسول اللہ ﷺ کے بعد غیر شرعی مطیع نبی بھی نہیں آسکتے جو آپ کی شریعت کے کامل
مصدق اور تابع ہوں تو پھر آپ سے یہ عہد کیوں لیا گیا کہ اگر آپ کے بعد مصدق نبی ظاہر ہوں تو ان
سے تعاون ہونا چاہیئے ظاہر ہے کہ اس جگہ خطاب آنحضرت ﷺ سے ہے لیکن مراد آپ کی
وساطت سے امت محمدیہ ہے اور ہر جگہ نبیوں سے لئے ہوئے عہد میں ان کے بعد آنے والے انبیاء
کے تعلق میں انکی امتیں ہی مراد ہوتی ہیں.ورنہ وہ نبی جو فوت ہو چکا وہ آئندہ آنے والے نبی کی کیسے
تائید کر سکتا ہے.اہل کتاب سے عہد :
صلى الله
پھر قرآن کریم اہلِ کتاب سے لئے گئے عہد کا الگ ذکر کرتا ہے جو میثاق النبین نہیں ہے بلکہ
جن لوگوں نے کتاب کو تسلیم کر لیا ہے ان کے ساتھ عہد کا مضمون شروع ہو جاتا ہے.معاہدات کے
تعلق میں کوئی ایک بھی پہلو نہیں جسے قرآن کریم نے تشنہ چھوڑ دیا ہو.اہلِ کتاب سے لئے گئے عہد کا
ذکر کرتے ہوئے قرآن مجید فرماتا ہے:
وَإِذْ اَخَذَ اللهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أوتُوا الْكِتَبَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا
تَكْتُمُوْنَهُ فَنَبَدُوْهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا
فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ
(آل عمران 3: 188 )
اب جب اللہ نے ان لوگوں کا میثاق لیا جنہیں کتاب دی گئی کہ تم لوگوں کی
Page 206
194
عدل، احسان اور ایتاء ذی القربی - حصه سوم
بھلائی کے لئے اس کو کھول کھول کر بیان کرو گے اور اسے چھپاؤ گے نہیں.پھر
انہوں نے اس (میثاق) کو اپنے پسِ پشت پھینک دیا اور اس کے بدلے
معمولی قیمت وصول کر لی.پس بہت ہی برا ہے جو وہ خرید رہے ہیں.یعنی ہم نے اہل کتاب سے ایک میثاق لیا تھا.عام عہد سے بڑھ کر میثاق کے لفظ میں عظمت
پائی جاتی ہے.ایک ایسا پختہ عہد جو دونوں طرف سے ہو جو TREATY کو اور اسکوتوڑنے والا
نقض عہد کا سنگین مجرم قرار دیا جائے.فرمایا جن کو کتاب دی گئی ہم نے ان سے یہ عہد لیا تھا کہ اس
کتاب کے تمام احکامات کو کھول کھول کر بیان کرنا اور خواہ کسی آیت کی گواہی تمہارے خلاف جاتی ہو
اس کے باوجود تمہارا یہ حق نہیں ہے کہ اس آیت کو چھپا لو بلکہ جس طرح تمہارے رسول پر وحی نازل
ہوئی بعینہ اسی طرح اس کے ہر پہلو کو کھول کر لوگوں کے سامنے رکھو پھر لوگوں پر چھوڑ دووہ نتیجہ اخذ کریں
کہ تمہارا استدلال درست ہے یا تمہارے مخالف علماء کا استدلال درست ہے.لیکن ضروری ہے کہ
دونوں پہلوؤں کو بلکہ ہر پہلو کو کھول کر بیان کرو.فرمایا " فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوُا
بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ، کتنی حسرت کی بات ہے کہ انہوں نے اس عہد کو پختگی کے باوجودا اپنی پیٹھوں کے
پیچھے پھینک دیا.اور کیوں پھینک دیا ؟ اس کے بدلہ ادنی دنیوی اموال پر راضی ہو گئے.پس جب بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے آنے والوں کی مخالفت کی جاتی ہے جیسا کہ حضرت محمد
مصطفی ﷺ کی مخالفت اس زمانے میں ہو رہی تھی اسکا نفسیاتی پس منظر بیان فرمایا گیا ہے.فرمایا
ہے اگر یہود عہد شکنی نہ کرتے اور اپنی بائیل کی وہ آیات بھی لوگوں کے سامنے پڑھ کر سناتے جن
آیات سے آنحضرت ﷺ کی تائید ہوتی تھی تو پھر ان پر کوئی حرف نہیں تھا پھر ہم نہیں کہ سکتے تھے کہ
یہ ٹیڑھی فطرتوں والے جھوٹے لوگ ہیں.فرمایا وہ تو یہ کام کرتے ہیں کہ بعض آیات کو چھپاتے ہیں
اور ان کو عامتہ الناس کے سامنے پیش نہیں کرتے گویا ان پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں چونکہ بالعموم عوام الناس
کو پوری کتاب کا علم نہیں ہوتا اس لئے وہ سمجھتے ہیں کہ اسی حد تک تعلیم ہے جو ہمارے علماء ہمیں بتا
رہے ہیں.جماعت احمدیہ کو اس دور میں ایسے ہی علماء سے واسطہ پڑا ہوا ہے.تعجب ہے کہ فی زمانہ
علماء جو اپنے زعم میں ختم نبوت کی حفاظت پر مامور ہو بیٹھے ہیں اس آیت پر کیوں غور نہیں کرتے اور
اگر کرتے ہیں تو عوام سے کیوں چھپاتے ہیں.بالعموم وہ اپنے وعظوں میں اس آیت کے ذکر ہی سے
اجتناب کرتے ہیں کیونکہ اس کا مضمون اس مضمون کے مخالف نظر آتا ہے جو انہوں نے ختم نبوت کا
سمجھ رکھا ہے.
Page 207
بندہ سے
خدا کا معاهده اور ذیلی معاهدات
195
پس دیکھئے قرآن کریم کس طرح فطرت انسانی پر بار یک نگاہ ڈالتا ہے اور دلوں کی بھی اور نفس
کی ٹھوکر کے ہر موقعہ کے متعلق کھلے الفاظ میں خبر دار کرتا ہے تاکہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لاعلمی کا عذر رکھ
سکیں.عہد شکنی قوموں کو ہدایت سے محروم کر دیتی ہے.خدا تعالیٰ سے شریعت کو قبول کر کے قومیں جو
عہد باندھتی ہیں اس عہد کو توڑنے کا محرک بھی بیان فرما دیا تا کہ انسان اس سے متنبہ رہے.فرمایا
فَنَبَدُوْهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا،
کہ وہ دنیا کے اموال یا دنیا کی لذتوں کی معمولی قیمت حاصل کر کے عہد توڑتے ہوئے خدا کی
رضا کو داؤ پر لگا دیتے ہیں.اسی طرح ان علماء پر بھی یہ آیت اطلاق پاتی ہے جنہوں نے دین کو اپنی
روزی کا ذریعہ بنایا ہوا ہوتا ہے اور چونکہ روزی کمانا مقصد اوّل ہے اس لئے دینی اقدار جب بھی
روزی کمانے کے مصالح سے ٹکراتی ہیں تو قربان کر دی جاتی ہیں.ہندو پاکستان کے اکثر علماء جن کی
ناء ونوش اپنی یا دیگر مسلمان حکومتوں کی خیرات پر منحصر ہے یا پرانے معاشرہ کے مطابق صاحب
حیثیت زمینداروں کی دی ہوئی روٹی پر گزر اوقات ہے ان کے لئے بڑی آزمائش ہے کہ وہ
رائج العام نظریات کے خلاف قرآن کریم کی ایسی گواہیاں پیش کریں جو ان کے رزق کی راہیں بند کر
دیں.مگر محض مجبوری کا عذر نہیں بلاشبہ ایسے بھی ملتے ہیں جن کے دل تقویٰ سے کلینتہ عاری ہیں اور
محض حب زر کی ہوس میں مبتلا ہو کر بکثرت ایسے جھوٹ بولتے ہیں اور کلام الہی کے ساتھ وفا میں
خیانت کے مجرم ٹھہرتے ہیں کہ جس کے نتیجہ میں وہ حکومتوں کے منظور نظر ہو جائیں یا عوام الناس میں
ایسی شہرت پا جائیں کہ ان کو بڑے بڑے دنیاوی اور مالی فوائد پہنچنے لگیں.جب یہ کیفیت پیدا ہو
جائے اور انحطاط یہاں تک پہنچ جائے تو پھر ایسے علماء قبول حق کے معاملہ میں بے حس ہو جاتے ہیں.یہاں تک کہ اگر خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی مصلح یا پیغمبر مبعوث کیا جائے تو یہی وہ علماء ہیں جو نہ
صرف انکار میں پہل کرتے اور شوخی دکھاتے ہیں بلکہ چونکہ دنیا کی خاطر دین کے عہد توڑنے کی
انہیں عادت پڑ چکی ہوتی ہے اور دنیا کی خاطر دین بیچنے کی شرم ٹوٹ چکی ہوتی ہے اس لئے ایسے
مواقع پر جب خدا کی طرف سے کوئی آنے والا انکو ہدایت کی طرف بلاتا ہے تو اس موقع کو بھی وہ دنیا
طلبی کے لئے ایک مزید ذریعہ بنالیتے ہیں.چنانچہ قرآن کریم نے اس حد سے بڑھی ہوئی بیماری کا
ذکر ان الفاظ میں فرمایا:
وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ (الواقعة 83:56)
یعنی کیا میرے پاک بندوں کی تکذیب ہی کو تم نے رزق کمانے کا ذریعہ بنالیا
Page 208
196
عدل، احسان اور ایتاء ذی القربی - حصه سوم
ہے.پس عہد شکنی کوئی معمولی گناہ نہیں یہ ایسا روحانی مرض ہے جو بڑھتا چلا جاتا
ہے اور بالآخر ہلاکت تک پہنچا دیتا ہے.قومی معاہدہ کی خلاف ورزی کی سزا:
ایک اور موقعہ پر قرآن کریم قومی معاہدہ کی خلاف ورزی کی سزا کا ذکر فرماتا ہے.فرمایا:
فَيَا نَقْضِهِمْ مِّيْثَاقَهُمْ لَعَثْهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوْبَهُمْ قُسِيَةً يُحَرِّفُونَ
لا
(المائدہ 14:5)
الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهِ ۖ وَنَسُوْا حَظَّا مِمَّا ذُكِرُوا بِهِ ۚ وَلَا تَزَالُ
تَطَّلِعُ عَلَى خَابِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحُ
اِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ
پس اُن کے اپنا عہد توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دلوں کو
سخت کر دیا.وہ کلمات کو ان کی اصل جگہوں سے ہٹا دیتے تھے اور وہ اس میں سے
جس کی انہیں خوب نصیحت کی گئی تھی ایک حصہ بھول گئے اور ان میں سے چند
ایک کے سوا تو ہمیشہ ان کی کسی نہ کسی خیانت پر آگاہ ہوتا رہے گا.پس ان سے
در گذر کر اور صرف نظر کر.یقینا اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے.اس آیت کریمہ میں قوموں
کو عہد شکنی پر دی جانے والی سزا کا ذکر فرماتا ہے اور وہ وجوہات
بیان فرماتا ہے جنہوں نے انہیں خدا کی عقوبت کا سزاوار بنا دیا.معمولی سے تدبر سے بھی یہ بات کھل
جاتی ہے کہ ہر سزا جس کا ذکر کیا گیا ہے وہ اس نوعیت کی ہے کہ اس کے نتیجہ میں پھر مزید سزائیں لازم
آتی ہیں.یعنی ایک جرم کے نتیجہ میں سزا یہ دی جارہی ہے کہ مزید جرم کرنے کی جسارت تمہیں ملے گی
یہ سلسلہ بڑھتے بڑھتے لازماً تمہیں ہلاکت تک پہنچا دے گا.پہلی سزا تو لعنت ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ بالعموم ایسی قوم جو عہد شکنی کرے خدا تعالیٰ سے دور
ہوتی چلی جاتی ہے اور تعلق باللہ کے آثار ان کی روز مرہ زندگی اور ان کے رہن سہن سے محو ہوتے چلے
جاتے ہیں.یہانتک کہ وہ ملعون کہلانے کے مستحق بن جاتے ہیں.دوسری سزا یہ بیان فرمائی گئی کہ
ایسی قوموں کے دل سخت ہو جاتے ہیں اور یہ دلوں کی سختی دینی امور میں بھی ظاہر ہوتی ہے اور دنیاوی
امور میں بھی.چنانچہ یہود کے دلوں کی سختی جواب ضرب المثل بن چکی ہے اسکی بنیادی وجہ بھی یہی
عبد شکنی قرار دی گئی مگر اس مضمون کا اطلاق عموماً ہر عہد شکنی کرنے والی قوم پر ہوتا ہے اور عہد شکنی کا دل
Page 209
بندہ سے
خدا کا معاہدہ اور ذیلی معاهدات
197
کی سختی سے ایک طبعی تعلق ہے.چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ عہد شکنی کرنے والے بنی نوع انسان کی
ہمدردی سے بھی محروم ہو جاتے ہیں اور سوسائٹی میں غریب اور محروم طبقے کی تکلیفوں اور مصائب سے
بے تعلق اور بے حس ہوتے چلے جاتے ہیں سوائے اس کے کہ نام اور دکھاوے کی خدمت خلق ہو.بظاہر عیسائی تو میں انسانی ہمدردی میں ایک خاص شہرت
رکھتی ہیں اور خود عیسائیت کی تعلیم اس
معاملہ میں ایک حسین تعلیم ہے لیکن بنظر غور دیکھیں تو بڑے بڑے عظیم الشان عیسائی ممالک کا
اقتصادی نظام ہی سخت دلی پر مبنی ہے.چنانچہ فی زمانہ رائج کیپٹلزم (capitalism) اور سود کا
عالمگیر نظام اہل کتاب سے تعلق رکھنے والی دو قوموں یعنی یہود اور نصاری کا مرہون منت ہے اور ادنیٰ
اور محروم اور غریب طبقے کی تکالیف اور مصائب کے احساس سے عاری یہ نظام امیر وغریب میں مزید
فرق کرتا چلا جاتا ہے.تیسری سزا یہ بیان فرمائی گئی کہ ایسی قومیں اپنے مطلب کی خاطر قوانین کو
توڑنے موڑنے اور من مانے مطالب نکالنے کی عادی بن جاتی ہیں.آجکل کی ڈپلومیسی کی جان اسی
مکر وفریب میں ہے.چنانچہ مذہبی دنیا میں بھی ایسی قوموں کے علماء خود اپنے الہی صحیفوں اور احکامات
سے اس قسم کا کھیل کھیلتے ہیں اور مطالب کو توڑنے موڑنے میں اور اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے میں
کوئی باک محسوس نہیں کرتے.ایک اور سزا یہ بیان فرمائی گئی کہ اگر چہ وہ پوری شریعت کو مکمل طور پر تو ترک نہیں کرتے لیکن اس
کے بعض حصوں کو اختیار کر لیتے ہیں اور بعض حصوں کو بھلا دیتے ہیں.ایسی قوموں کی تاریخ کے
مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ واقعتہ عہد شکن قوموں نے یہی رخ اختیار کیا اور کلیتہ دین سے منحرف
نہیں ہوئیں بلکہ بعض حصوں سے چھٹی رہیں اور بعض حصوں کو متروک کر دیا.قرآن کریم کے مطابق
اس
کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ قومیں بالعموم خائن بن جاتی ہیں اور خدا ہی کے معاملہ میں نہیں دنیا میں بھی ایک
دوسرے سے خیانت کرنا ان کا شعار بن جاتا ہے سوائے ان چند لوگوں کے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل
سے اس بیماری سے محفوظ رکھتا ہے.یعنی ساری قوم سو فیصدی بدنہیں ہوا کرتی بلکہ اکثریت بد ہو جاتی
ہے اور بہت تھوڑی تعداد نیکی پر قائم رہتی ہے.پس سرسری مطالعہ سے بھی صاف ظاہر ہے کہ یہ
ساری سزائیں وہ ہیں جو دراصل سزائیں نہیں بلکہ بیماریوں کے نتائج ہیں.اس نقطۂ نگاہ سے عدل کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ عہد شکنی ، ترک عدل کی ایک سنگین
صورت ہے اور اس کے نتیجہ میں صرف ایک بیماری نہیں بلکہ مسلسل بڑھنے والی متعدد بیماریاں انسان
کو چمٹ جاتی ہیں جو بالآخر اس کے لئے مہلک ثابت ہوتی ہیں.جہاں ان سزاؤں کا بیان ہے وہاں
خود خدا تعالیٰ کی طرف سے عدل کی ایک بہت ہی پیاری مثال بھی پیش کر دی گئی.خدا تعالیٰ کسی قوم
Page 210
198
عدل، احسان اور ایتاء ذی القربی - حصه
سوم
کے خلاف فتویٰ دینے میں ایسی عمومیت اختیار نہیں کرتا کہ ساری قوم کو ہی یک قلم مردود قرار دیدے
بلك إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ میں بالخصوص مومنوں کو متوجہ فرمایا کہ جہانتک تمہارا تعلق ہے تم کسی قوم کو
بحیثیت قوم تمام تر خائن اور بددیانت اور بد عہد قرار نہیں دے سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ
ان میں سے بعض نیک اور سچے اور انصاف پسند لوگ بھی ہوتے ہیں.جہاں تک بندے کا تعلق ہے
دوسرے کو متہم کرنے میں اس پر بہت احتیاط لازم ہے کیونکہ وہ عالم الغیب نہیں.ایک اور جگہ عہد شکنی
کی سزاؤں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا:
أوليك لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ (الرعد 26:13 )
ہی وہ لوگ ہیں جن کے لئے لعنت ہے اور ان کے لئے بدتر گھر ہوگا.یعنی ایسے لوگوں پر خدا کی لعنت کی ماراس رنگ میں پڑتی ہے کہ ہر معاملہ میں یہ لوگ بد انجام ہو
جاتے ہیں.سوء الدَّارِ “ کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آخرت میں انکا ٹھکانہ برا ہو گا اور ان کا
آخری گھر ان کے لئے بہت ہی تکلیف دہ ثابت ہوگا.جرم اور سزا میں باہمی مناسبت :
اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کو اس کے نقض عہد کی ایسی سزا دی ہے جو اس کے عہد کے ساتھ مناسبت
رکھتی ہے.چنانچہ فرمایا:
وَمِنَ الَّذِيْنَ قَالُوا إِنَّا نَصْرَى أَخَذْنَا مِيْثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا
مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء إِلى يَوْمِ الْقِيمَة
وَسَوفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ) ( المائدة 15:5)
اور اُن لوگوں سے ( بھی ) جنہوں نے کہا کہ ہم نصاری ہیں ہم نے ان کا میثاق
لیا پھر وہ بھی اس میں سے ایک حصہ بھلا بیٹھے جس کی انہیں تاکیدی نصیحت کی گئی
تھی.پس ہم نے ان کے درمیان قیامت کے دن تک باہمی دشمنی اور بغض
مقدر کر دیئے ہیں اور اللہ ضرور اُن کو اس ( کے بدانجام ) سے آگاہ کرے گا جو
صنعتیں وہ بنایا کرتے تھے.خدا تعالیٰ جرم کے مطابق سزا دیتا ہے انہوں نے ایک حصہ کی نافرمانی کی تو اسی کے مطابق ان
پر سز لازم آتی ہے.قرآن کریم نے اس موقعہ پر سزا تو معین کر دی ہے لیکن یہ نہیں فرمایا کہ عیسائیت
Page 211
بندہ سے
خدا کا معاہدہ اور ذیلی معاهدات
199
کی کس تعلیم سے انہوں نے روگردانی کی تھی جسکی انہیں یہ سزا دی گئی.لیکن چونکہ سزا کو جرم سے ایک
مناسبت ہوتی ہے اس لئے سزا کا ذکر ہی ان کے جرائم کے چہرہ سے بھی پردہ اٹھا دیتا ہے.سزا یہ ہے کہ وہ قیامت تک ایک دوسرے سے باہمی نفرت کرتے رہیں گے اور بغض کا شکار
ہونگے.یعنی عیسائی قوموں میں ہمیشہ باہمی جنگ و جدل جاری رہے گا.چنانچہ عیسائی دنیا میں ہمیں
یہی نظارہ نظر آتا ہے.پہلی جنگ عظیم میں ہم نے یہی دیکھا، دوسری جنگ عظیم میں یہی دیکھا.یہ
در اصل عیسائی قوموں کی عالمی جنگوں کا فتنہ تھا جس کا آپ نے مشاہدہ کیا اور ان میں البغضاء کی
کیفیت ایسی بتائی گئی ہے جس کے متعلق فرمایا کہ قیامت تک چلتی چلی جائے گی.اس کے علاوہ بھی
ان کی کالونیل تاریخ میں مختلف ممالک کو زیرنگیں کرنے میں جب بھی آپس میں ان کے مفادات
ٹکراتے ہیں تو ہر ایسے موقعہ پر یہ سخت چپقلش کا شکار ہو جاتے ہیں.گویا ایک واحد انصاف کا پیمانہ
سامنے نہیں رہتا اور ہر ایک یہی کہتا ہے کہ ہم انصاف پر ہیں.چنانچہ تقسیم ہندوستان میں بھی یہی
ہوا.افریقہ کے ممالک میں بھی یہی تاریخ دہرائی گئی.امریکہ میں بھی شمال سے جنوب تک یہی
اندرونی چپقلش ہے جس نے عیسائی دنیا کو آپس میں بانٹے رکھا ہے.سیاسی سطح پر ایسی چپقلش جو
مسلسل ایک تاریخ کا حصہ بن جائے اور خطر ناک جنگوں کی صورت پر منتج ہو.یہ وہ سزا ہے جسکا
قرآن کریم نے وضاحت کے ساتھ ذکر کیا ہے.پس یہ استنباط بعید از قیاس معلوم نہیں ہوتا کہ وہ جرم
جسکی یہ سزا تھی یہ تھا کہ حضرت عیسی علیہ السلام کی تعلیم کے مطابق ایک خدا کو تسلیم کرنے کے باوجود
انہوں نے خدا کی شخصیت کو پھاڑ دیا.یعنی ظاہری خدا ایک ہی رہا مگر اندرونی طور پر شخصیت پھٹ
گئی.پس وہ سزا جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں اس جرم سے عین مطابقت رکھتی ہے.نقض عہد کی مزید سزائیں:
قرآن کریم عہد شکنی کی مختلف سزائیں مختلف جرائم کو پیش نظر رکھ کر بیان فرما رہا ہے.غالبا دنیا
کی کسی مذہبی کتاب میں اس طرح جرم بہ جرم ایک منطقی نتیجہ کے طور پر انکی سزاؤں کا بیان نہیں ملے
گا.ہاں کسی حد تک بائبل میں بعض جرموں کی بعض سزائیں معین طور پر بیان ہوئی ہیں.ان سب کا
تجزیہ کرتے ہوئے ان کے مقابل کی سزاؤں کا ایسا ذکر قرآن کریم ہی کی شان ہے اور یہ سزائیں
ہمیشہ کسی معین مذہب کے حوالہ سے نہیں بتائی جار ہیں بلکہ ان جرائم کا بھی ذکر ہے جو بالعموم بنی نوع
انسان میں مذہب کے تعلق میں ملتے ہیں اور ہر مذہب والے اپنے بگڑے ہوئے دور میں بالعموم
ایسے ہی جرائم میں ملوث ہو جاتے ہیں.پس اس تعلق میں اسلام یا یہودیت یا عیسائیت یا ہندومت
Page 212
200
عدل، احسان اور ایتاء ذی القربی - حصه سوم
وغیرہ کو الگ الگ زیر بحث نہیں لایا گیا بلکہ مذہبی قوموں کے انحطاط کے وقت جو جو نفسیاتی بیماریاں
عموماً سر اٹھاتی ہیں.ان کا قسموں کے طور پر ذکر کر دیا گیا ہے.چنانچہ فرمایا:
إِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلًا أُولَبِكَ لَا خَلَاقَ
لَهُمُ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيِّمَةِ
وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ ( آل عمران 78:3
یقینا وہ لوگ جو اللہ کے عہدوں اور اپنی قسموں کو معمولی قیمت میں بیچ دیتے ہیں
یہی ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا اور اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا
اور وہ قیامت کے دن ان پر نظر نہ ڈالے گا اور انہیں پاک نہیں کرے گا.اور ان
کے لئے دردناک عذاب ( مقدر) ہے.یعنی وہ لوگ جو اللہ کے عہد کے بالمقابل ادنی ادنی قیمتیں لے کر عہد شکنی پر آمادہ ہو جاتے ہیں
گویا خدا کے عہد کو تھوڑے سے مول لے کر ذلیل سی دنیا کی چیزوں کی خاطر بیچ ڈالتے ہیں انہوں
نے دنیا کی خاطر دنیا کمانے کے لئے اللہ سے منہ پھیرا ہے اسکی مناسب حال نہایت دردناک سزا یہ
ہوگی کہ قیامت کے دن انہیں کچھ نہیں ملے گا اور اللہ ان سے منہ پھیر لے گا.مگر اس سے بہت بڑی
سزا یہ بیان
فرمائی گئی کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے کلام نہیں فرمائے گا.عموماً آیت کے اس حصہ کو پڑھ کر
ذہن اخروی زندگی کی طرف چلا جاتا ہے.پڑھنے والا سمجھتا ہے کہ قیامت کے دن خدا تعالیٰ ان
سے کلام
نہیں کرے گا اگر چہ یہ معنی بھی درست ہے مگر محض یہی معنی نہیں.پس جو اس دنیا میں کلام الہی
سے محروم رہ جائے یعنی بطور سزا یہ اسکا مقدر بن گیا ہو اخروی دنیا میں بھی یہی سزا زیادہ شدید اور
دردناک طور پر اس کو ملے گی.پھر فرمایا وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمُ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں.اس حصہ کا تعلق بھی دراصل
محض آخرت سے نہیں بلکہ اس دنیا سے بھی ہے.پھر " وَلَا يُز كُيْهِمْ “ کہہ کر یہ فرمایا کہ خدا تعالیٰ
یز
ان کو پاک نہیں کرے گا.آیت کے اس حصہ نے مضمون کو بالکل کھول دیا ہے اور اس بات کا کوئی شبہ
باقی نہیں رہنے دیا کہ یہ محض آخرت کی باتیں نہیں ہیں بلکہ اس دنیا میں ہونے والے قدرتی سلوک کا
بھی ذکر ہو رہا ہے.تزکیہ کا وقت تو اس دنیا میں ہوا کرتا ہے.نظر رکھنے سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ خدا کی نگاہ سے باہر رہتا ہے.کوئی چیز خدا کی نگاہ سے
باہر نہیں.مراد محض اس کیفیت کا اظہار ہے جو ناراضگی کے نتیجہ میں پیدا ہوتی ہے گویا کوئی انسان کسی کو
Page 213
بندہ سے
خدا کا معاہدہ اور ذیلی معاهدات
201
دیکھنا پسند نہیں کرتا.پس نظر نہ ڈالنے کا معنی یہاں یہ لیا جائے گا کہ ان پر شفقت کی نظر نہیں ڈالتا،
اسے قبولیت کی نظر سے نہیں دیکھتا.خدا تعالیٰ ہر چیز کا خالق و مالک ہے اور کلی اختیار رکھتا ہے اس کے باوجود عہد کے بارہ میں ایک
ایسا عدل کا معاملہ بندوں سے کرتا ہے کہ فرمایا:.وَأَوْفُوا بِعَهْدِى أَوْفِ بِعَهْدِكُمْ (البقرة 41:2)
کہ عہد دوطرفہ ہو ا کرتا ہے.مجھ پر بھی یہ اسی طرح فرض ہے جیسے تم پر.میں
نے عہد باندھا ہے اور میں اقرار کرتا ہوں کہ تم عہد کی پابندی کرتے چلے جاؤ
میں بھی عہد کی پابندی کرتا چلا جاؤں گا.ایفائے عہد کی جزاء:
پاس عہد میں اب تک عہد شکنی کا ذکر چل رہا تھا اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان نیک بندوں کا
کس رنگ میں ذکر فرماتا ہے جو اپنے عہدوں کو پورا کرتے ہیں
فرماتا ہے:
الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيْثَاقَ وَالَّذِينَ
يَصِلُونَ مَا اَمَرَ اللهُ بِمَ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَ
يَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ وَالَّذِيْنَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمُ
وَأَقَامُوا الصَّلوةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ
بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ جَثْتُ عَدْنٍ
يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ بَابِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ
وَالْمَلَكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابِ (الرعد 21:13 24)
(یعنی) وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کئے ہوئے) عہد کو پورا کرتے ہیں اور
میثاق کو نہیں توڑتے.اور وہ لوگ جو اُ سے جوڑتے ہیں جسے جوڑنے کا اللہ نے
حکم دیا اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور برے حساب سے خوف کھاتے ہیں.اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی رضا کی خاطر صبر کیا اور نماز کو قائم کیا اور جو
کچھ ہم نے ان کو دیا اس میں سے چھپا کر بھی اورا علانیہ بھی خرچ کیا اور جو
Page 214
202
عدل، احسان اور ایتاء ذی القربی - حصه سوم
نیکیوں کے ذریعہ برائیوں کو دور کرتے رہتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے لئے
گھر کا ( بہترین) انجام ہے.(یعنی) دوام کی جنتیں ہیں.ان میں وہ داخل
ہوں گے اور وہ بھی جو ان کے آباء و اجداد اور ان کے ازواج اور ان کی
اولادوں میں سے اصلاح پذیر ہوئے.اور فرشتے ان پر ہر دروازے سے
داخل ہو رہے ہوں گے.اللہ تعالیٰ یہاں فرماتا ہے کہ جو کچھ بھی اپنے رب سے پاتے ہیں اس میں سے وہ خرچ کرتے
ہیں اعلانیہ بھی چھپ چھپ کے بھی.کیونکہ وہ ریا کاری نہیں چاہتے اور اعلانیہ بھی تا کہ لوگ ان سے
نمونہ پکڑ کرنیکیوں میں ترقی کریں.اور وہ ہمیشہ جب بُرائی کو دور کرتے ہیں تو نیکی کے بدلہ دور کرتے
ہیں، اچھی چیز پیش کر کے دور کرتے ہیں.پس ہر بدی جس کا قرآن میں ذکر موجود ہے اس کے
مقابل پر لاز ما اس نوع سے تعلق رکھنے والی نیکی کا بھی ذکر ہے.پس جھوٹ کو دور کرتے ہیں تو سچ کے
ذریعہ ظلم کو دور کرتے ہیں تو رحم اور شفقت کے ذریعہ.ويَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ كَا
ویساہی مطلب ہوگا جیسا فرمایا گیا کہ جاء الحق و زهق الباطل.یہ ایسے ہی ہے جیسے کہا جائے
کہ دن چڑھ گیا اور اندھیر از ائل ہو گیا ہے.جیسی اخلاقی تعلیم انسانوں کو دی گئی ویسی ہی تعلیم کا اللہ تعالیٰ خودا اپنے آپ کو پابند
کرتا ہے:
قرآن کریم کی ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو اس بات کا پابند فرماتا ہے کہ ان
نشانات کے بدلہ میں جنہیں اس نے منسوخ فرما دیا ہے یا مٹنے دیا ہے کم سے کم ویسے ہی اور نشانات
لے آتا ہے بلکہ ان سے بھی بہتر.یہ اصول حسب ذیل آیت کریمہ میں بیان فرمایا گیا ہے.مَا نَنُسَخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا
( البقرة 107:2)
ترجمہ: جو آیت بھی ہم منسوخ کر دیں یا اُسے بھلا دیں ، اُس جیسی یا اس سے
بہتر ضرور لے آتے ہیں.یہ آیت عموماً علماء سابقہ کی طرف سے قرآن کریم کی دوسری آیات کی تنسیخ کے تعلق میں بیان کی
جاتی ہے.یعنی خدا تعالیٰ جب قرآن کریم کی بعض آیات منسوخ فرماتا ہے تو ان کے بدلہ ویسی ہی اور
Page 215
بندہ سے خدا کا معاهده اور ذیلی معاهدات
203
آیات یا ان سے بہتر نازل فرما دیتا ہے.حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم کی کوئی آیت بھی کسی دوسری
آیت کو منسوخ نہیں کرتی.اور تنسیخ کے بعد ویسی ہی آیت یا اس سے بہتر آیات نازل نہیں کی جاتیں.اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے پرانے علماء اپنے زعم میں پانچ سوایسی آیات کی نشاندہی کرتے
ہیں جنہیں پانچ سو دوسری آیات نے منسوخ کر دیا ہے.پھر پا تو ویسی ہی پانچ سو آیات ان منسوخ
شدہ آیات کی جگہ نازل کی گئیں یا ان سے بہتر آیات.وہ کونسی آیات تھیں جنہوں نے اپنی جیسی
دوسری آیات کو بلا وجہ منسوخ کیا؟ اس سوال کا کوئی جواب نہیں دیا جا تا.اسی طرح وہ کونسی بہتر
آیات ہیں جو ان کی جگہ نازل کی گئیں.ان
کا بھی کوئی مدلل ذکر نہیں ملتا.دراصل یہ محض پرانے علماء کا
ناسخ و منسوخ کا غلط عقیدہ تھا کہ جس کی تائید میں انہوں نے اس آیت کا سہارا لینے کی کوشش کی ہے.قرآن کریم کی یہ آیت ناسخ و منسوخ کے عقیدہ سے کوئی بھی تعلق نہیں رکھتی.ہاں اس میں
آیات سے مراد خدا تعالیٰ کے نازل کردہ گزشتہ مذاہب ہیں.جب کبھی ایسا ہوا، ان جیسے اور مذاہب
ان کی جگہ لینے کیلئے نازل فرما دئے گئے لیکن جب زمانہ کی ضرورت نے تقاضا کیا تو اس نئی ضرورت
کے پیش نظر پہلوں کی جگہ نئی یا ترقی یافتہ مذاہب نازل فرما دئے گئے.اس طرح مذاہب کا ارتقا
جاری رہا یہاں تک کہ اسلام کے ظہور پر یہ ارتقا مکمل ہو گیا.انفرادی معاہدات:
اب تک جن عہدوں کا ذکر گزرا ہے وہ اجتماعی نوعیت کے تھے.اب ہم انفرادی نوعیت کے
معاہدات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں.جن کا تعلق بندہ اور خدا کے ساتھ انفرادی طور پر باندھے ہوئے
عہدوں سے ہے یا بندوں کے بندوں کے ساتھ انفرادی طور پر باندھے ہوئے عہدوں سے ہے.چنانچہ فرمایا:
مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ
قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا
(الاحزاب 24:33)
مومنوں میں ایسے مرد ہیں جنہوں نے جس بات پر اللہ سے عہد کیا تھا اسے سچا
کر دکھایا.پس ان میں سے وہ بھی ہے جس نے اپنی منت کو پورا کر دیا اور ان
میں سے وہ بھی ہے جو ابھی انتظار کر رہا ہے اور انہوں نے ہرگز (اپنے طرز عمل
میں ) کوئی تبدیلی نہیں کی.
Page 216
204
عدل، احسان اور ایتاء ذی القربی - حصه
سوم
حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے چا حضرت انس بن النضر غزوہ بدر کے
وقت موجود نہیں تھے.آپ رسول ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یارسول اللہ !
میں اس پہلی جنگ کے وقت جو آپ نے مشرکین سے لڑی تھی موجود نہیں تھا.اگر اللہ نے مجھے آئندہ
مشرکین سے لڑائی کا موقعہ دیا تو اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ میں کیا کرتا ہوں.پس اپنی محرومی کے غم کے
ازالہ کیلئے انہوں نے خدا سے ایک عہد باندھا.کچھ اسی قسم کی سوچوں میں مبتلا ہونگے کہ اللہ تعالیٰ
نے اس آیت میں منجملہ جن پیارے بندوں کا ذکر فرمایا ان میں یہ خوش نصیب بھی شامل ہوئے.چنانچہ جنگ احد کے دوران ایک ایسا موقعہ بھی آیا کہ کفارا چانک اس طرح پلٹ پڑے کہ مسلمان
اس کی توقع نہیں رکھتے تھے اور ایک سراسیمگی کا عالم طاری ہوا اور بڑے بڑے جیالوں اور وفاداروں کے
پاؤں بھی اکھڑ گئے.یہاں تک کہ قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ آنحضرت یہ تن تنہا میدان کارزار
میں کھڑے اپنے ساتھیوں کو بلا رہے تھے.یہ وہ وقت تھا کہ جب کہ زخموں کی تاب نہ لا کر آنحضرت
ایک گڑھے میں گر گئے اور لاشوں نے آپ کو ڈھانپ لیا.اس وقت دشمن یہ سمجھا کہ وہ
آنحضور ﷺ کوقتل کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے.اس وقت کچھ مسلمان ٹولیاں جگہ جگہ ابھی
برسر پر کار تھیں مگر جب دشمن کا یہ اعلان سنا کہ محمد ﷺ کوقتل کر دیا گیا ہے تو جو سراسیمگی کا عالم طاری ہوا
وہ نا قابل بیان ہے.اس وقت حضرت انس کی روایت کے مطابق حضرت انس بن النضر نے کہا.اے اللہ ! میں ان (مسلمانوں ) کے اس فعل سے تیرے حضور معذرت چاہتا ہوں اور جوان
(مشرکین ) نے کیا ہے اس سے بھی بیزاری کا اظہار کرتا ہوں.پھر وہ آگے بڑھے تو سعد بن معاد
سے ملاقات ہوئی.انہوں نے کہا.اے سعد بن معاذ ! نضر کے رب
کی قسم جنت (سامنے ہے).مجھے احد کے اس جانب سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے.حضرت سعد بن معادؓ نے حضور ﷺ کو بتایا
کہ یارسول اللہ ! جو جوانمردی انہوں نے دکھائی وہ میری بساط سے باہر ہے.حضرت انس فرماتے
ہیں کہ جب ( جنگ کے بعد ) ہم نے انہیں پایا تو ان کے جسم پر اسی (۸۰) سے زیادہ تلواروں ،
تیروں اور نیزوں کے زخم تھے.مشرکین نے ان کے کان ، ناک وغیرہ کاٹ لئے تھے جس کے
باعث کوئی انہیں پہچان نہ سکا جبکہ صرف ان کی بہن نے انگلیوں کے پوروں سے انہیں پہچانا.حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہمارا خیال اور گمان ہے کہ قرآن کریم کی آیت ” مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالُ
صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ.....الخ “ ان کے بارہ میں اور ان جیسے دیگر حضرات کے بارہ
میں نازل ہوئی ہے.(46)
Page 217
بندہ سے
خدا کا معاہدہ اور ذیلی معاهدات
205
انفرادی معاہدہ اور عہد شکنی کی سزا:
اس کے برعکس قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ ذاتی عہد باندھنے والے بد نصیب ان
عہدوں
کو توڑ دیتے ہیں.فرمایا:
وَمِنْهُم مَّنْ عُهَدَ اللهَ لَبِنْ أَتْنَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّ قَنَّ وَ
لَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّلِحِيْنَ فَلَمَّا أَتُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَ
تَوَلَّوْا وَّهُمْ مُّعْرِضُونَ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقَا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ
يَلْقَوْنَهُ بِمَا اَخْلَفُوا اللهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُوْنَ.(التوبه 75:9 تا 77)
اور ان ہی میں سے ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر وہ ہمیں
اپنے فضل سے کچھ عطا کرے تو ہم ضرور صدقات دیں گے اور ہم ضرور نیک
لوگوں میں سے ہو جائیں گے.پس جب اس نے اپنے فضل سے انہیں عطا کیا
تو وہ اس میں بخل کرنے لگے اور (اپنے عہد سے ) پھر گئے اس حال میں کہ وہ
اعراض کرنے والے تھے.پس عقوبت کے طور پر اللہ نے ان کے دلوں میں
اس دن تک کیلئے نفاق رکھ دیا جب وہ اس سے ملیں گے بوجہ اس کے کہ انہوں
نے اللہ سے وعدہ خلافی کی نیز اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے.شخص
اس نقض عہد کی ایک مثال حدیث میں یوں ملتی ہے کہ آنحضرت لم ﷺ کے زمانہ میں ایک شخص
حضور اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا.اس نے کہا یا رسول اللہ ! میں بہت غریب ہوں، غربت
سے تنگ آ گیا ہوں.میرے لئے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے رزق میں برکت ڈالے اور مجھے اپنے
فضل سے بہت مال و دولت عطا فرمائے.اس نے یہ اظہار کیا کہ اگر خدا مجھے دے گا تو میں اس طرح
بڑھ بڑھ کے اسکی راہ میں قربانیاں دوں گا.آنحضرت ﷺ نے اس کیلئے دعا کی اور اس کے مال میں
ایسی برکت پڑی کہ کثرت کے ساتھ اسکی بھیڑ بکریاں اور مال مویشی بڑھنے لگے.جب
کے نمائندے اس سے زکوۃ لینے گئے تو اس نے جواب میں کہا کہ کسی کا مال دیکھ کر تم
زکوۃ لینے کیلئے آجاتے ہو لیکن یہ پتہ نہیں کہ کوئی کسی محنت سے کماتا ہے اور یونہی مفت میں مال ہاتھ
نہیں آجاتا.غرضیکہ اسی طرح اس نے بڑھ بڑھ کر باتیں بنائیں اور وہ نمائندے اس سے بغیر کچھ
وصول کئے آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس واقعہ کی آپ کو اطلاع دی.یہ سن کر
آنحضرت ﷺ نے یہ حکم صادر فرمایا کہ آئندہ اس سے بھی خدا کے نام پر کوئی مال نہیں لیا جائے گا.صلى الله
Page 218
206
عدل، احسان اور ایتاء ذی القربی - حصه سوم
روایات میں آتا ہے کہ دیر کے بعد اسے احساس ہوا کہ میں اپنی جان پر ظلم کر بیٹھا ہوں.وہ آیا
اور آنحضرت مے سے معافی مانگی کہ میں اب سب کچھ دینے کیلئے تیار ہوں مگر آپ نے فرمایا کہ
کبھی ایسا نہ ہوگا.چنانچہ آنحضرت ﷺ کے وصال کے بعد پھر وہ حضرت ابوبکر کی خدمت میں
حاضر ہوا اور کہا رسول اللہ اللہ کا تو وصال ہو چکا ہے میں مال پیش کرنا چاہتا ہوں قبول کیا جائے.حضرت ابو بکر نے کہا کہ جس کے مال کو محمد رسول اللہ ﷺ فرما چکے ہیں ابو بکر بن ابی قحافہ کون ہوتا
ہے اسکو قبول کرنے والا.پھر وہ حضرت عمرؓ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کے یہی پیشکش کی.انہوں
نے بھی یہی کہا کہ عمر کون ہوتا ہے کہ جس کا مال رسول اللہ علے رد فرما دیں اسے عمر قبول کرلے.غرضیکہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس کا مال بڑھتا چلا گیا اور اس نے عمر بھی اتنی پائی کہ یکے بعد دیگرے
ایک خلیفہ کے بعد دوسرے خلیفہ کی خدمت میں حاضر ہو کر مال قبول کرنے کی درخواست کرتا رہا مگر
ہر درخواست رد کر دی گئی.(47)
دوسروں کو کیا پتہ کہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو خدا سے منافقانہ رویہ اختیار کرتے ہیں.بعض
دفعہ دوسروں کو بھی اس کی خبر ہو جاتی ہے جیسا کہ مذکورہ واقعہ کی اطلاع ہم تک پہنچی.مگر یہ بھی ممکن ہے
کہ ایسے منافقین دنیا کو دھوکہ دیں اور خدا کی خاطر سب کچھ قربان کرنے کی بڑھ بڑھ کے باتیں
کریں.یہ دھو کہ اس وقت تک ایسا ملتا ہے جب تک خدا ان کے پردے چاک نہیں کر دیتا.جماعت
احمدیہ میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے لتھی مالی قربانی کا ایک مضبوط اور مستحکم نظام چل رہا ہے.بعض
اوقات بعض لوگ یہ تعلی کرتے ہیں کہ وہ اپنا سب کچھ خدا کی خاطر قربان کرنے کیلئے تیار ہیں.اگر چہ ایسے لوگ تعداد میں بہت تھوڑے ہیں مگر پھر بھی جماعت کی اس اکثریت کے ساتھ یہ بھی ملے
رہتے ہیں جو اپنے عہدوں میں پوری طرح مخلص ہیں.جب آخر خدا ایسے منافقین کو ننگا کرنے کا
فیصلہ کرتا ہے تو ان کی منافقانہ چال ظاہر کر دی جاتی ہے.پس یہ وعدے کے بعد مالی کمزوری
یا مجبوری کی وجہ سے اسے پورا نہ کرنے والوں کا ذکر نہیں ہے بلکہ محض ان کا ذکر ہے جن کی نیت میں
آغا ز ہی سے نفاق شامل ہوتا ہے.اسی مضمون پر قرآن کریم کی دیگر کئی آیات بھی روشنی ڈالتی ہیں.آنحضرت ﷺے عہد شکن کو منافق قرار دیتے ہیں.جیسا کہ اس حدیث میں ہے.فرمایا:
اذا عاهد غدر
کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے اور دھوکہ دیتا ہے.(8
(48)
اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر چہ نفاق کا تعلق دل سے ہے مگر اس کی کچھ علامتیں جب باہر
پھوٹ پڑیں تو منافق کی نشان دہی بھی ہو جایا کرتی ہے.
Page 219
غیروں سے معاهدات
21.غیروں سے معاہدات
207
قرآن کریم کی یہ خاص شان ہے
کہ تمام عہدوں کو انسانی سطح پر یکساں قابل عمل دکھایا ہے اور
قومی یا دینی دائروں میں کسی عہد کو محدود نہیں فرمایا یہ وہ تعلیم ہے جو کل عالم سے یکساں تعلق رکھتی ہے
اور ہر زمانہ پر یکساں چسپاں ہوسکتی ہے.چنانچہ فرمایا:
إِلَّا الَّذِيْنَ عُهَدْتُّمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَ
لَمْ يُظَاهِرُ وَاعَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ
اِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ
(التوبه 4:9)
سوائے مشرکین میں سے ایسے لوگوں کے جن کے ساتھ تم نے معاہدہ کیا پھر
انہوں نے تم سے کوئی عہد شکنی نہیں کی اور تمہارے خلاف کسی اور کی مدد بھی نہیں
کی.پس تم ان کے ساتھ معاہدہ کو طے کردہ مدت تک پورا کرو.یقیناً اللہ
متقیوں سے محبت کرتا ہے.ی کیسی عظیم الشان عدل
کی تعلیم ہے.فرمایا ہم تمہیں صرف ان ہی عہدوں کا پابند نہیں کر ر ہے جو تم
ہم سے کرتے ہو یا ہمارے نبی سے کرتے ہو.اس میں اس بات کا بھی کوئی دخل نہیں کہ جس سے عہد
کر رہے ہو وہ طاقتور ہے یا کمزور ہے یا نیک ہے یابد.بلکہ عہد کی پابندی تمہیں ہر ایک اصول کے طور
پر ہر پہلو سے کرنی ہوگی.مشرکوں سے عہد کی بھی وہی وقعت بیان فرمائی ہے جو ہر کسی دوسرے عہد کی
بیان کی گئی ہے.ہاں اگر ان کی طرف سے پابندی عہد میں کمزوری کے آثار ظاہر ہوں اور ایسی علامتیں
سامنے آئیں جن سے معلوم ہو کہ وہ عہد شکنی کی تیاری کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں اسی حد تک جوابی
کاروائی کیلئے تیار رہنے کا حکم دیا گیا ہے.یہ مراد نہیں کہ عہد شکنی کے خوف کے نتیجے میں عہد توڑ دو بلکہ
جس حد تک وہ کاروائی کرتے ہیں اسی حد تک جوابی کاروائی کی اجازت ہے.چنانچہ فرمایا:-
وَامَّا تَخَافَنَ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ
اللهَ لَا يُحِبُّ الْخَابِنِيْنَ
(الانفال 59:8)
اور اگر کسی قوم سے تو خیانت کا خوف کرے تو ان سے ویسا ہی کر جیسا انہوں
نے کیا ہو.اللہ خیانت کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا.
Page 220
208
عدل، احسان اور ایتاء ذی القربی - حصه سوم
آنحضرت ﷺ کے اسوہ سے ثابت ہے کہ آپ نے کبھی ایک موقعہ پر بھی دشمن کی طرف سے
عہد شکنی کے خوف سے اپنے عہد کو نہیں توڑا.جب تک دشمن کی طرف سے عہد شکنی کا آغاز نہیں ہوا
آپ نے جوابی کارروائی نہیں فرمائی.ہاں عہد شکنی کے آثار ظاہر ہونے کے نتیجہ میں انسدادی اور
جوابی کارروائی کی تیاری ضرور کی ہے اور اس طرح عہد شکن دشمن کو آپ نے کبھی یہ موقعہ بھی نہیں دیا
کہ وہ اچانک بے خیالی میں آ پکڑے اور مسلمان ایسے حملے کیلئے تیار نہ ہوں.غیروں سے معاہدات کی دو قسمیں:
اب میں آپ کو بتا تا ہوں کہ غیروں سے دو قسم کے معاہدات ہو سکتے ہیں.ایک ہے دبی ہوئی حالت کا معاہدہ جب مومن مجبور ہے اور دبا ہوا ہے او اس میں یہ صورت
حال بھی عملاً واضح فرما دی کہ کس حد تک انسان دب کر اپنا حق چھوڑ سکتا ہے اور ایسا حق چھوڑنا نہ
بزدلی ہے اور نہ اخلاقی تقاضوں سے انحراف.ہاں اس کے برعکس یہ بھی اجازت نہیں دی کہ وقتی
مصلحتوں پر کسی اصول کو قربان کر دیا جائے.یعنی حق اس حد تک چھوڑا جائے گا کہ بنیادی اصولوں
سے متصادم نہ ہو.معاہدہ صلح حدیبیہ:
دبی ہوئی حالت کا معاہدہ صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہے.اس
کی بعض اہم شرائط حسب ذیل تھیں.محضرت ﷺ اور آپ کے ساتھی اس سال واپس چلے جائیں اور نہ عمرہ کریں
ا.الله
نہ حج کریں.باوجود یکہ آنحضرت ﷺ اور آپ کے صحابہ بہت تکلیف اٹھا کے ایک ایسے مقصد کے لئے
آئے تھے جس سے روکنے کا مشرکین کا کوئی حق نہیں تھا.اسکے باوجود آپ نے جب اپنا حق چھوڑا
ہے تو کیا یہ اصول
کی قربانی نہیں؟ یہ وہ سوال ہے جس کا سیر حاصل جواب ضروری ہے.فی الواقعہ یہ
بات اصول سے متصادم اسلئے نہیں کہ ایک اور اصول ہے وہ بھی قرآن کریم ہی کا بیان فرمودہ ہے
جولازم کرتا ہے کہ بعض حالات میں تمہیں اس حق کو چھوڑنا ہو گا اور وہ حالات یہ ہیں کہ اگر رستے کے
امن کے ساتھ بغیر کسی قتال کے تم خانہ کعبہ کا حج نہ کر سکو تو پھر حج نہیں کرنا.پس یہ بالا اصول اس طوعی
حق سے قطعیت کے ساتھ محروم کر رہا ہے.پس آنحضرت ﷺ نے کسی قرآنی اصول کی قربانی کر
کے نہیں بلکہ قرآنی اصول کی تائید میں یہ قربانی پیش کی ہے.
Page 221
غیروں سے
معاهدات
209
آئندہ سال وہ مکہ میں آکر رسم عمرہ ادا کر سکتے ہیں مگر سوائے نیام میں بند تلوار
کے کوئی ہتھیا ر ساتھ نہ ہو اور مکہ میں تین دن سے زیادہ نہ ٹھہریں.یشق ، پہلی شق کو مزید نرم کر دیتی ہے اور صرف وقت کی تعین کا مسئلہ رہ جاتا ہے.گویا بصورت
دیگر انہوں نے مسلمانوں کا بنیادی حق تو تسلیم کر لیا مگر اس پر تاخیر کے ساتھ عمل کرنے کی اجازت
دی.جہاں تک تلواروں کا نیام میں رکھنا ہے وہ تو عین حج اور عمرہ کی روح کے مطابق بات تھی.اس
میں بھی آنحضرت ﷺ نے کسی بنیادی حق یا اصول کی قربانی نہیں دی..صلى الله
اگر کوئی مرد مکہ والوں میں سے مدینہ جائے تو خواہ وہ مسلمان ہی ہو
آنحضرت ﷺ اسے مدینہ میں پناہ نہ دیں اور واپس لوٹا دیں.چنانچہ اس تعلق میں صحیح بخاری کے
الفاظ یہ ہیں لا پاتیک منا رجل و ان کان علی دینک الا رددته الینا.یعنی ہم میں سے
اگر کوئی مرد آپ کے پاس جائے تو آپ اُسے واپس لوٹا دیں گے.لیکن اگر مسلمان مدینہ کو چھوڑ کر مکہ میں آجائے تو اسے واپس نہیں لوٹایا جائے گا.اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اگر مکہ والوں میں سے کوئی شخص اپنے ولی یا گارڈین کی اجازت
کے بغیر مدینہ آ جائے تو اسے واپس لوٹا دیا جائے گا.جہاں تک کسی مسلمان کے مدینہ سے مکہ جا کر بسنے کا تعلق ہے تو یہ مدینہ کے ہر شخص کا حق تھا کہ
جہاں چاہے جاکر زندگی بسر کرے.جہاں تک کسی مسلمان کے مکہ سے نکل بھاگنے کا تعلق ہے چونکہ
اس وقت تک مشرکین کو مکہ پر حکومت حاصل تھی اور عملاً انہوں نے بہت سے مسلمانوں کو قیدی بنایا
ہوا تھا اسلئے انکا قانون ان کے روک رکھنے کا حق رکھتا تھا.پس یہاں ہر گز کسی اصول کی قربانی نہیں ہے نہ پہلی شق میں اور نہ دوسری شق میں.ہاں تسلیم
کر لیا گیا ہے کہ ان بھاگے ہوئے قیدیوں کو مدینہ میں پناہ نہیں دی جائے گی تا کہ اہل مدینہ ان کے
فرار میں ملوث نہ سمجھے جائیں.معاہدہ پر پابندی کا جہاں تک تعلق ہے رسول ﷺ اس بارہ میں اس
حد تک محتاط تھے کہ اس وقت جب ابھی معاہدہ کی ان شرائط پر گفتگو ہورہی تھی اور ابھی معاہدہ طے پا کر
اس پر دستخط نہیں ہوئے تھے تب بھی رسول اللہ اللہ نے یہ عظیم کردار دکھایا کہ عین اس وقت جب یہ
شرط ابھی زیر بحث تھی اچانک قریش مکہ کے سفیر سہیل بن عمرو کا بیٹا ابو جندل بیڑیوں اور ہتھکڑیوں
میں جکڑا ہوا گرتا پڑتا اس مجلس میں آپہنچا.اس نوجوان کو اہل مکہ نے مسلمان ہونے پر قید کر لیا تھا.جب اسے معلوم ہوا کہ آنحضرت ﷺ مکہ کے اس قدر قریب تشریف لائے ہوئے ہیں تو وہ کسی
طرح گرتا پڑتا حدیبیہ میں پہنچ گیا اور اپنے آپ کو مسلمانوں کے سامنے لا ڈالا اور دردناک آواز میں
Page 222
210
عدل، احسان اور ایتاء ذی القربی - حصه سوم
پکار کر کہا کہ اے مسلمانو! مجھے محض اسلام قبول کرنے کی وجہ سے یہ عذاب دیا جا رہا ہے.خدا کیلئے
مجھے بچاؤ.مسلمان اس نظارہ کو دیکھ کر تڑپ اٹھے مگر اس کا باپ یعنی مکہ کا سفیر سہیل بھی اپنی ضد پر
صلى الله
اڑ گیا اور آنحضرت ﷺ سے کہنے لگا کہ یہ پہلا مطالبہ ہے جو میں اس معاہدہ کے مطابق آپ سے
ے
کرتا ہوں اور وہ یہ کہ ابو جندل کو میرے حوالہ کر دیں.آپ نے فرمایا ”ابھی تو معاہدہ تکمیل کو نہیں
پہنچا، سہیل نے کہا اگر آپ نے ابو جندل کو نہ لوٹایا تو پھر اس معاہدہ کی کارروائی ختم سمجھیں.آنحضرت ﷺ نے فرمایا.آؤ آؤ جانے دو اور ہمیں احسان و مروت کے طور پر ہی ابوجندل
کو دے دو سہیل نے کہا نہیں نہیں یہ
کبھی نہیں ہوگا.آپ نے فرمایا سہیل ضد نہ کرو میری یہ بات
مان لو سہیل نے کہا میں یہ بات ہر گز نہیں مان سکتا.اس موقعہ پر ابو جندل نے پھر پکار کر کہا.اے
مسلمانو! کیا تمہارا ایک مسلمان بھائی اس شدید عذاب کی حالت میں مشرکوں کی طرف واپس لوٹا
دیا جائے گا؟.یہ ایک عجیب بات ہے کہ اس وقت ابو جندل نے آنحضرت ﷺ سے اپیل نہیں کی
بلکہ عامة المسلمین سے اپیل کی جس کی وجہ غالباً یہ تھی کہ وہ جانتا تھا کہ آنحضرت ﷺ کے دل
میں خواہ کتنا ہی درد ہو آپ کسی صورت میں معاہدہ کی کاروائی میں رخنہ نہیں پیدا ہونے دیں گے.آنحضرت ﷺ نے کچھ وقت خاموش رہ کر ابو جندل سے درد مندانہ الفاظ میں فرمایا.اے
ابو جندل ! صبر سے کام لو اور خدا کی طرف نظر رکھو.خدا تمہارے لئے اور تمہارے ساتھ کے دوسرے
کمزور مسلمانوں کیلئے ضرور خود کوئی رستہ کھول دے گا.لیکن ہم اس وقت مجبور ہیں کیونکہ اہل مکہ کے
ساتھ معاہدہ کی بات ہو چکی ہے اور ہم اس معاہدہ کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے“.اس معاہدہ پر سرسری نظر سے غور کرنے والا اندازہ ہی نہیں لگا سکتا کہ رسول اللہ کے اس بظاہر
دب کر فیصلہ قبول کرنے میں کتنی گہری حکمت تھی اور اس سے کتنا بڑا فائدہ اسلام کو پہنچا ہے.آپ نے
یہ نہیں فرمایا کہ جو مکہ سے بھاگ کر مدینہ جائے گا میں اسے مجبور کروں گا کہ تمہارے پاس واپس
جائے.آپ نے فرمایا کہ ہم اسے مدینہ میں پناہ نہیں دیں گے.باقی دنیا میں وہ جہاں چاہے اس
کے پناہ کے حق کا انکار نہیں فرمایا.کچھ عرصہ کے بعد اہل مکہ کو محسوس ہو گیا کہ وہ معاہدہ جو بظاہر ان کے
حق میں تھا حضرت رسول اللہ ﷺ کے الفاظ کے محتاط چناؤ کی وجہ سے ان کے مفاد کے خلاف نکلا.اگر وہ رسول اللہ کی قیادت میں انہیں مدینہ رہائش اختیار کرنے کی اجازت دیدیتے تو ان کی مجال نہ
ہوتی کہ وہ رسول اللہ ﷺ کی مرضی کے خلاف معاہدہ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اہل مکہ پر حملہ
کر سکتے.مگر مکہ سے بھاگنے والے چونکہ مدینہ میں نہ بس سکتے تھے اسلئے انہوں نے درمیان میں کہیں
Page 223
غیروں سے معاہدات
211
اپنی الگ بستیاں بنالیں جہاں سے بلا روک ٹوک مکہ سے شمال کی طرف جانے والے قافلوں پر حملے
کرتے تھے.چنانچہ ان بھاگنے والوں نے اہل مکہ کی زندگی اجیرن کر دی.میثاق مدینہ
معاہدہ کی ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ہر وہ فریق جو معاہدہ میں شریک ہو، خواہ وہ کسی بھی
مذہب کا ہو، اسے برابر کے حقوق حاصل ہوں گے.میثاق مدینہ اس قسم کے معاہدہ کی ایک نمایاں
مثال تھی.اس معاہدہ کی اہم شرائط یہ تھیں.ا.قریش مہاجر اور مدینہ کے انصاری اہل مدینہ جوان کے ساتھ اس عہد میں شامل
ہوں گے کہ اگر مدینہ پر حملہ ہو جائے تو مدینہ کے دفاع میں وہ سب اکٹھے ہو جائیں گے.یہ سب
لوگ اختلاف مذہب کے باوجود ایک ہی امت شمار ہوں گے.اس معاہدہ کی پہلی شق کی بقیہ شرائط نہیں لکھی جار ہیں کیونکہ ان کا زیر نظر مضمون سے براہ راست
تعلق نہیں ہے.نہیں بنے گا.کوئی مومن اپنے مومن بھائی کی مرضی کے بغیر اس کے مولیٰ غلام یا دوست کا حلیف
مومن لوگ ان میں سے جو بھی ظلم کرے گا یا جو گناہ کی بات کرے گا یا عدوان کرے
گا یا مومنوں کے درمیان فساد پیدا کرے گا سب اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے خواہ ایسا کرنے
والا انکا باپ ہی کیوں نہ ہو.۴.خلاف مددکر لگا.۵.حصہ پائے گا..کوئی مومن کسی مومن کو کافر کی خاطر قتل نہیں کریگا اور نہ ہی کسی کافر کی کسی مومن کے
خدا کی امان سب کیلئے برابر ہے.ان میں سے حقیر ترین شخص بھی اس میں سے اپنا
یہود میں سے جو اس معاہدہ میں شامل ہوگا اس کو بھی مومنوں جیسے حقوق حاصل ہوں
گے.نہ ان پر ظلم ہوگا، نہ ان کے خلاف کسی کی مدد کی جائے گی.سب مومنوں کے امن کی حالت ایک جیسی ہی ہے.کوئی مومن اپنے مومن ساتھی کو
چھوڑ کر اپنے دشمن کے ساتھ صلح نہیں کریگا.اگر ان میں کوئی غلطی سے کسی مومن کو قتل کر یگا تو اسے خون بہادینا ہو گا سوائے اس
Page 224
212
عدل، احسان اور ایتاء ذی القربی - حصه سوم
کے کہ ورثاء معاف کر دیں.اگر وہ خون بہانہ دے تو سب اس کے خلاف کھڑے ہونگے.اس معاہدہ میں شامل لوگوں میں اگر کوئی جھگڑا ہوگا جس کے فتنہ کا اندیشہ ہو تو اسے
و.خدا اور اس کے رسول محمد کی طرف لوٹایا جائے گا.+17
ا.قریش کفار اور ان کے مددگاروں
کو پناہ نہیں دی جائے گی.اگر کوئی مدینہ پر حملہ کرے تو شرکاء معاہدہ ایک دوسرے کی مدد کریں گے اور اگر صلح
کی پیشکش ہو تو سب شامل ہوں گے.۱۲.مومنوں پر بھی پابندی ہے کہ وہ شرکاء کے ایسے حقوق مانیں اور ادا کریں سوائے
اسکے جو دین کی خاطر جنگ کرے.۱۳.اس معاہدہ سے ظالم یا گنہگار کوکوئی پناہ نہیں ملے گی.الد
مدینہ سے باہر جانے والا بھی امن کا حق رکھتا ہے اور مدینہ میں رہنے والا بھی.۱۵.جو نیکی اختیار کرے گا خدا اس کا ساتھی ہے اور محمد رسول اللہ بھی“.اس معاہدہ سے صاف ظاہر ہے کہ یہ حکومت کی قانون سازی نہیں بلکہ معاہدہ کی شقیں ایسی
ہیں جو معاشرت کے اصولوں کے مطابق ہیں چنانچہ اس کا مرکزی نکتہ اس بات میں ہے کہ اگر یہود
اس معاہدہ میں شامل ہوں تو ان کو بھی مومنوں جیسے حقوق حاصل ہونگے.اس معاہدہ کی رُو سے ہر
شریک معاہدہ خواہ وہ مدینہ میں رہے یا مدینہ کو چھوڑ کر باہر کہیں بسنے کیلئے چلا جائے ، برابر امن کا
حقدار ہوگا.معاہدہ کے شرکاء کا کوئی حق نہیں ہوگا کہ ان کے معاملہ میں دخل دیں.یہ میثاق ایک ایسا
چارٹر ہے جو آئندہ زمانہ میں بھی تمام جھگڑے والی قوموں کیلئے ان کے درمیان انصاف کے ساتھ
فیصلہ کرنے کا بہترین ذریعہ ثابت ہوسکتا ہے.اس معاہدہ کی رُو سے اس بات کا کوئی جواز نہیں رہتا کہ بڑی اور طاقتور قوموں کو چھوٹی اور کمزور
قوموں کے مقابلہ پر اپنا فیصلہ ٹھونسنے کا کوئی حق دیا جائے.جو قوم بھی کسی دوسری قوم پر ظلم کرنے سے
باز نہ آئے اس کے خلاف باقی سب قوموں کو جو اقوام متحدہ میں شامل ہوں، اجتماعی کارروائی کرنی
پڑے گی.یعنی ایسی صورت میں سب پر برابر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اکٹھے ہو کر دونوں جھگڑنے
والی قوموں کو سمجھائیں کہ فوری طور پر مخالفانہ کاروائیاں بند کر دیں.اس کے بعد دونوں کا فرض ہے کہ
اپنے جھگڑے باہم طے شدہ ثالثی کے ذریعہ طے کروائیں.اس معاہدہ پر عمل درآمد کے طریق میں بھی رسول اللہ ﷺ کا ایک اسوہ ہے جو اس معاہدہ کی
Page 225
غیروں سے معاهدات
213
تشریح کرتا ہے کہ یہود جب اپنا مقدمہ لے کر آتے ہیں تو رسول اللہ کی بالا دستی جو اس معاہدہ میں
مسلّم ہے اس کا آنحضور ﷺ نے یہ مطلب نہیں سمجھا کہ آپ اپنے دین کو شریک معاہدہ دوسرے
دین والوں پر ٹھونسیں بلکہ بلا استثناء ان کو اختیار دیا کہ چاہو تو تمہاری شریعت کے مطابق فیصلہ ہواور
چاہو تو اسلامی شریعت کے مطابق اور چاہو تو رواج کے مطابق.صلى
معاہدات کی پابندی میں اسوہ رسول صلی اللہ :
معاہدات کی پابندی کے سلسلہ میں اب میں آنحضرت ﷺ کی پاکیزہ زندگی سے بعض مثالیں
آپ کے سامنے رکھتا ہوں.ایک دفعہ آنحضرت ﷺ کی خدمت میں ایک قاصد آیا جو کسی قوم کی طرف سے ایک پیغام لایا تھا.وہ آپ سے ملاقات کے بعد اسلام لے آیا اور باوجود اسکے کہ اس کے بیوی بچے اور اس کے اہل وعیال اور
اسکے مال و متاع سب پیچھے تھے اس نے کہا کہ یا رسول
اللہ ! اب تو میرا واپس جانے کو دل نہیں چاہتا.مجھے اجازت دیں میں یہاں آپ ہی کے قدموں میں ٹھہر جاؤں.آنحضرت ﷺ نے فرمایا
میں بدعہدی کا مرتکب نہیں ہوسکتا.تم قاصد ہو.تمہیں بہر حال واپس جانا چاہیئے.“ قاصد کو یہ
اجازت نہیں ہے کہ وہ پیغام لے کر آئے اور پھر واپس نہ لوٹے.کیسی شان
کی تعلیم ہے.اگر یہ معاملہ
رسول اکرم ﷺ کے سامنے نہ آیا ہوتا تو ہم میں سے بہت سے منصف مزاج طبعا یہ کہتے سو بسم اللہ ،
شوق سے بیٹھو.تم اپنی مرضی سے ٹھہر رہے ہو تمہیں یہ جگہ پسند آ گئی ہے، ہم آزاد ہو.بہر حال حضرت
محمد رسول اللہ ﷺ نے اس کو یہ اختیار ضرور دیا کہ ہاں اگر پھر واپس آنا چا ہوتو آ جانا اس سے کوئی
انکار نہیں.چنانچہ وہ گیا اور چونکہ وہ بھی سچا تھا اپنے دل سے مجبور تھا.کچھ عرصہ کے بعد ان لوگوں سے
بھاگ کر پھر آ گیا.اس دفعہ وہ قاصد نہیں تھا بلکہ ایک مہاجر کے طور پر آپ کی خدمت میں حاضر
ہو گیا.(49)
آنحضرت ﷺ کے پاس حضرت حذیفہ بن یمان مکہ سے ہجرت کر کے بدر کے موقعہ پر آپ
کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے آپ سے عرض کیا کہ جب میں مکہ سے نکلا تھا تو قریش
نے یہ شبہ کر کے کہ شاید میں آپ کی مدد کیلئے جارہا ہوں مجھ سے یہ عہد لیا تھا کہ میں آپ کی طرف
سے ہو کر نہ لڑوں گا.تو آپ نے فرمایا کہ پھر جاؤ تم اپنے عہد کو پورا کرو، ہمیں ہمارا خدا کافی ہے.(50)
سبحان اللہ ! آپ کے توکل کی کیا شان ہے ورنہ یہ کہہ سکتے تھے کہ جو عہد دباؤ کے تحت
(Under duress) لیا جائے اس عہد کی پابندی لازم نہیں رہتی.افسوس کہ آج مسلمان
Page 226
214
عدل، احسان اور ایتاء ذی القربی - حصه سوم
کہلانے والے ملاں کا دین آنحضور میلے کے اس مسلک سے بہت دور ہٹ چکا ہے.پھر آنحضرت ﷺ نے اپنے غلاموں کے ایسے عہد کی بھی پابندی فرمائی جو وہ عہد کرنے کے
آنحضرت علی کی طرف سے مجاز نہیں تھے.یہاں عہد کی پابندی کا مضمون عدل سے بڑھ کر احسان
میں داخل ہو جاتا ہے.حضرت ام ہانی بنت ابی طالب بیان کرتی ہیں کہ میں فتح مکہ کے سال
آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئی.آنحضور ﷺ ایک کپڑے میں لیٹے ہوئے نماز پڑھ
رہے تھے.آپ نے آٹھ رکعتیں پڑھیں ، میں انتظار کرتی رہی.پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ !
میں ہیرہ کے فلاں بیٹے کو پناہ دے چکی ہوں اور یہ کہنے سے انکی مراد یہ تھی کہ میں نے یہ پناہ اپنے
طور پر دی ہے اور دیگر صحابہ کے اتفاق یا آپ کی اجازت سے نہیں دی.لیکن میرے ماں جائے علی
یعنی میرے سگے بھائی اسے قتل کرنے پر تلے بیٹھے ہیں.رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ” قد اجرنا من
(51)
اجرت یا ام هانی“.اے ام ہانی! جسے تو نے پناہ دیدی اسے ہم نے بھی پناہ دیدی.ظاہر ہے کہ آنحضرت ﷺ اس پناہ کی پشت پناہی پر پابند نہیں تھے.کوئی انصاف کا قانون
بھی آپ پر یہ لازم نہیں کرتا جہاں تک عدل کا تقاضا ہے.تاہم اپنوں میں سے انفرادی طور پر کسی
کے فعل پر صاد کرنا احسان کے طور پر ہوسکتا ہے.مسلمانوں کے سیاسی ادبار سے متعلق ایک پیشگوئی:
مسلمانوں کو عہد شکنی سے باز رکھنے کیلئے آنحضرت ﷺ نے ایک عجیب نکتہ بیان فرمایا.آپ
نے بطور پیشگوئی فرمایا:
تُنْتَهَى ذِمَّةُ اللَّهِ وَ ذِمَّةً رَسُولِهِ اللهِ فَيَشُدُّ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ قُلُوْبَ
اهل الزِّمَّةِ فَيَمْنَعُونَ مَا فِى أَيْدِيهِمْ.(صحيح بخارى كتاب الجزية
باب اثم من عاهد ثم غدر
کہ جب اللہ کے ذمہ (عہد ) اور اس کے رسول ﷺ کے عہد کو توڑا جائے گا تو
اللہ تعالیٰ کا فروں کے دلوں کو سخت کر دے گا اور وہ اپنے مال میں سے تمہیں کچھ
بھی نہیں دیں گے.(52)
اگر اس نکتہ کو مسلمان حکومتیں ملحوظ رکھتیں تو وہ کبھی بھی ضائع نہ ہوتیں.مسلمانوں کی سلطنتوں میں
دو دور آئے ہیں.اول دور میں جب مسلمان اپنے ذمہ لوگوں کے عہد کا خیال رکھتے تھے، ان کی
Page 227
غیروں سے معاہدات
215
ضرورتوں کا خیال کیا کرتے تھے، ان کے حقوق کی حفاظت کرتے تھے، تو اس وقت ان کی رعایا ان
سے محبت اور احترام کا تعلق رکھتی تھی اور اختلاف مذہب اس تعلق کی راہ میں کبھی حائل نہیں ہوسکا.پس وہ قوم جو اپنے عہدوں کی حفاظت کرتی ہے وہ پورے کئے ہوئے عہد خود اس قوم کی حفاظت
کرتے ہیں.تاریخ اسلام میں اس مضمون کی تائید میں ایک ایسا نمایاں واقعہ ملتا ہے جو بار بار بیان
کے لائق ہے.ایک بار رومیوں کے زبردست دباؤ کی وجہ سے اسلامی لشکر حمص سے پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گیا.مسلمانوں نے اس علاقہ سے وصول شدہ سارا خراج وہاں کے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے واپس کر دیا کہ
ہم نے تمہاری حفاظت اور اس علاقہ کے امن و امان کو برقرار رکھنے کی شرط پر یہ ٹیکس وصول کیا تھا.اب ہم اس علاقہ کو چھوڑ رہے ہیں اور اس پوزیشن میں نہیں کہ تمہاری حفاظت کر سکیں.اس پر اہل حمص
نے جو جواب دیا اسے تاریخ کے اوراق نے ان سنہری حروف میں محفوظ کیا ہے.انہوں نے کہا:
”ہم اپنے ہم مذہب لوگوں کے ظلم وستم کا نشانہ بنے ہوئے تھے ان حالات میں تم آئے.تمہاری حکومت اور تمہارے عدل نے ہمیں اپنا گرویدہ بنالیا.اب ہم تمہارے مقرر کردہ گورنر کے
ساتھ مل کر ہر قل کے لشکر سے لڑیں گے اور ہمیں مار کر ہی وہ آگے بڑھ سکے گا.“
(53)
چنانچہ یہ سارا علاقہ رومیوں کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا.ہر قل پسپا ہوا اور مسلمان دوبارہ اس علاقہ
میں فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے تو وہاں کے باشندوں نے ان کا پر جوش استقبال کیا بڑے بڑے
جلوس نکالے اور ادائے خراج اور وفاداری کے نئے سرے سے عہد و پیمان ہوئے.اس دور کے بعد جس کی ایک نیک مثال بیان کی گئی ہے بدنصیبی سے ایک دوسرا دور آیا جب
مسلمان حکومتوں نے اپنے ماتحتوں کے حقوق کی حفاظت چھوڑ دی اور تعلیم قرآن کی رو سے حاکم اپنی
رعایا کے مفادات کی حفاظت کا جس طرح پابند ہے اس کی پرواہ نہ کی تو رعایا بھی ان سے غافل اور
بے تعلق ہوگئی اور یہ توڑے ہوئے عہد ان کی حکومتوں کے ٹوٹنے اور زوال کا موجب بن گئے.معاہدات کی پابندی کی بعض اور مثالیں :
انفرادی طور پر آنحضرت علیہ غیر کے حقوق کی ایسی حفاظت کرتے تھے اور ذمیوں کے حقوق
کے متعلق ایسی شدت سے
تعلیم دیتے تھے کہ آپ کے تربیت یافتہ صحابہ کا نمونہ اسی رنگ میں ڈھالا
گیا جس رنگ میں آنحضرت ﷺ نے ان کو تعلیم دی.حضرت عمرؓ کے زمانہ میں ایک یہودی قتل
ہو گیا اور اس کے قتل کا سراغ نہیں ملتا تھا.حضرت عمرؓ کو اس کا علم ہوا تو گھبرا کر باہر نکل آئے اور صحابہ
Page 228
216
عدل، احسان اور ایتاء ذی القربی - حصه سوم
کو مسجد میں اکٹھا کیا اور منبر پر چڑھ کے اتنا دردناک اور زور دار خطبہ دیا کہ دیکھو میں کیا کروں گا خدا
نے میرے ہاتھ میں بنی نوع انسان کی باگ ڈور تھمائی ہے.میں کیا جواب دوں گا مخلوق خدا کا خون
ہو گیا.خدا مجھ سے پوچھے گا تو کیا کر رہا تھا.اتنا دردناک خطبہ تھا کہ قاتل اسی وقت اٹھ کے کھڑا
ہو گیا.اس نے کہا.اے امیر المومنین! میں قاتل ہوں، مجھے سزا دیں، آپ تکلیف میں نہ مبتلا
ہوں.(54) بلاشبہ قاتل کو اس کے بعد قتل کر دیا گیا.اللہ اس کی روح کو سلامتی عطا فرمائے.یہ ہے
ذمہ کی تعلیم جو آنحضرت ﷺ نے اپنی قوم کو دی اور اس شان کے نظارے عملاً پیدا فرما دیے.حضرت علی کے پاس ایک دفعہ ایک مسلمان پکڑ کے لایا گیا جس نے ایک ذمی کو قتل کیا تھا.پورا
ثبوت موجود تھا اسلئے حضرت علیؓ نے قصاص میں اس مسلمان کے قتل کئے جانے کا حکم دیا.قاتل کے ورثاء نے مقتول کے بھائی کو معاوضہ دے کر معاف کرنے پر راضی کر لیا.حضرت علی
کو جب اس کا علم ہوا تو آپ نے اس کے بھائی سے فرمایا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ان لوگوں نے تجھے
ڈرا دھمکا کر تجھ سے کہلوایا ہو کہ تم اسے معاف کر دو.آپ نے مقتول کے بھائی کو اس کے حقوق سے
آگاہ کیا.اس نے کہا مجھ پر کوئی دباؤ نہیں.میں یہ فیصلہ اس لئے کر رہا ہوں کہ قاتل کے قتل کئے
جانے سے میرا بھائی تو واپس آنے سے رہا اور اب یہ مجھے اس کی دیت دے رہے ہیں جو پسماندگان
کیلئے کسی حد تک کفایت کرے گی اس لئے خود اپنی مرضی سے بغیر کسی دباؤ کے معافی دے رہا ہوں.اس پر حضرت علیؓ نے فرمایا یہ تمہارا حق ہے اس کے بعد میں اس کے قتل کا حکم نہیں دیتا لیکن ہماری
حکومت کا اصول یہی ہے کہ " من كان له ذمتنا فدمه کد منا و دیته کدیتنا “ یعنی جو ہماری
زمی رعایا میں سے ہے اس کا خون ہمارے خون کی طرح ہے اور اس کی دیت ہماری دیت ہی کی
طرح ہے.(55)
اس کے بعد حاضرین جلسہ کو کچھ نصائح کی گئیں اور دعائیں دی گئیں جن کا اس کتاب کے
قارئین سے کوئی تعلق نہیں اس لئے انہیں مقرر کی اجازت سے حذف کیا جارہا ہے.(ناشر)
Page 229
217
حوالہ جات حصہ سوم
(43)
(44)
(45)
(46)
(47)
(48)
(49)
(50)
المفردات فی غریب القرآن.زیر لفظ قرع، صفحه 417.مولف: ابوالقاسم الحسين بن محمد
المعروف بالراغب الأصفهاني ناشر: داراحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت لبنان.الطبعة الاولى.1423ه ، 2002ء.سنن ابن ماجه.ابواب الرهون.باب تلقيح النخل.روایت نمبر 2471 تالیف: ابو عبدالله محمد
بن يزيد الربعي ابن ماجه القزويني ناشر: دار السلام للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة
الاولى.محرم 1420ھ ،اپریل 1999ء.صحیح بخاری، کتاب احادیث الانبياء، باب حديث الغار.روایت نمبر 3478.مولف:ابوعبدالله
محمد بن اسماعيل البخاري الجعفى.ناشر: دار السلام للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة الثانية
ذو الحجة 1419ھ ، مارچ 1999ء
صحیح بخاری، کتاب الجهاد والسير، باب قول الله عزوجل : من المومنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله
عليه.......روايـت نـمبـر 2805.مولف:ابـو عبـدالـلـه مـحـمـد بـن اسـمـاعـيـل البـخـارى
الجعفى.ناشر: دارالسلام للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة الثانية ذو الحجة 1419ه، مارچ 1999ء.الدر المنثور في التفسير المأثور جلد3، صفحه 467 تا 468 تفسیر آیات سورة التوبة،75تا78.تاليف: جلال الدين عبدالرحمان بن ابوبكر السيوطى ناشر : دار الكتب العلمية، بيروت
لبنان.الطبعة الاولى 1411ه ، 1990ء
اسدالغابة، ذكر ثعلبه بن حاطب بن عمرو بن عُبيد....الانصارى الاوسي.جلد 1، صفحه 272،
273.مولف: ابو الحسين علی بن محمد الجزرى.ناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع،
بیروت لبنان الطبعة الثانية.1422ه.2001 ء.صحیح بخاری، کتاب الایمان ، باب علامات المنافق روايت نمبر 34 مولف: ابو عبدالله محمد
بن اسماعيل البخاري الجعفى.ناشر: دار السلام للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة الثانية ذو الحجة
ھ، مارچ 1999ء
1419
سنن ابو داؤد، كتاب الجهاد ، باب فی الامام يستجن به فى العهود.روایت نمبر 2758.مولف: ابوداؤد سلیمان بن الاشعث بن اسحاق الازدى السجستاني.ناشر: دار السلام للنشر
والتوزيع، الرياض، الطبعة الاولى.محرم 1420ھ.اپریل 1999ء.صحیح مسلم، کتاب الجهاد، باب الوفاء بالعهد.روایت نمبر 4639.تالیف: امام ابوالحسين مُسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابورى.ناشر: دارالسلام للنشر والتوزيع، الرياض.طبع اوّل: 1419ھ ، جولائی 1998ء
Page 230
عدل، احسان اور ایتاء ذی القربی - حصه سوم
صحیح بخارى، كتاب الجزية والموادعة.باب امان النساء وجوارهن.روایت نمبر 3171.مولف: ابوعبدالله محمد بن اسماعيل البخاري الجعفى ناشر: دار السلام للنشر والتوزيع، الرياض،
الطبعة الثانية ذو الحجة 1419ه ، مارچ 1999ء
صحیح بخارى، كتاب الجزية والموادعة، باب اثم من عاهد ثم غدر روايت نمبر 3180.مولف: ابو عبدالله محمد بن اسماعيل البخاري الجعفي.ناشر: دار السلام للنشر و التوزيع، الرياض، الطبعة الثانية ذو الحجة 1419ھ ، مارچ 1999ء.فتوح البلدان صفحه 143 144.مولف: احمد بن يحيى بن جابر البغدادي الشهير بالبلاذرى.ناشر: شركة طبع الكتب العربية.مطبع : الموسوعات بشارع باب الخلق بمصر.الطبعة الاولى 1319.اسد الغابه،ذکر بکر بن شداخ ،جلد1،صفحه234.مولف: ابوالحسين علی بن محمد الجزرى.ناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع بيروت لبنان الطبعة الثانية.1422ه، 2001ء.نصب الرأية لاحاديث الهداية.جلد ۴ صفحه ۳۳۷.مولف : جمال الدین ابو محمدعبدالله بن
يوسف الحنفى الزيلعي ناشر: المجلس العلمى، سورت(الهند).الطبعة الاولى.1357.1938ء مطبعة دار المامون بشبرا شارع الازهار رقم 1.22
218
(51)
(52)
(53)
(54)
(55)
Page 231
عدل، احسان
اور
ايتاء ذى القربى
تین بنیادی تخلیقی اصول
چهارم
خطاب فرمودہ جلسہ سالانہ اسلام آباد، یو کے 24 جولائی 1988ء
حضرت مرزا طاهر احمد
خليفة المسيح الرابع رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى
22- قول میں عدل
23- بنی نوع انسان کے مابین قیام عدل کا بنیادی اصول
24.رشتہ داروں کے متعلق عدل و احسان کی تعلیم
Page 233
إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَ ابْتَائِ ذِي الْقُرْلِى وَيَنْهَى
عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِي يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ
(النحل 91:16)
یقینا اللہ عدل کا اور احسان کا اور اقرباء پر کی جانے والی عطا کی طرح
عطا کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی اور ناپسندیدہ باتوں اور بغاوت سے
منع کرتا ہے.وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تا کہ تم عبرت حاصل کرو.اس سے پہلے عدل و احسان اور ایتاء ذی القربی پر جو
بحثیں گزرچکی ہیں، ان کے علاوہ اس مضمون کے بعض اور پہلوا بھی
تشیر تکمیل ہیں ، جن پر اب بحث کی جائے گی.تمام تر تعلیم جو
قرآن کریم نے دی ہے اسے ہم حضرت اقدس محمد مصطفی ملے کے
اسوہ میں بعینہ ڈھلا ہوا دیکھتے ہیں.یہ اصول قول میں عدل پر بھی
چسپاں ہوتا ہے.
Page 235
قول
میں
عدل
22- قول میں عدل
223
ہم ایک دفعہ پھر قول میں عدل کے مضمون پر گفتگو کرنے لگے ہیں مگر جو باتیں پہلے بیان کی
گئی ہیں ان
کی دہرائی نہیں کی جائے گی صرف بعض دیگر پہلوؤں پر روشنی ڈالی جائے گی.اس پہلو سے اب میں نے انسانی طبقات کو مختلف حصوں میں تقسیم کرتے ہوئے ان کے
حقوق کے متعلق بعض قرآنی آیات اور ارشادات نبوی کا انتخاب کیا ہے قول میں عدل وہ جڑ ہے جس
سے عدل کا مضمون پھوٹتا ہے اور پھیلتا چلا جاتا ہے.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:
وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبى (الانعام 153:6)
کہ جب بھی تم کوئی بات کہو قول میں عدل اختیار کرو خواہ اپنے کسی قریبی کے
خلاف ہی کیوں نہ ہو.اس سلسلہ میں یہ بات خاص طور پر پیش نظر رہنی چاہیے کہ قول کا عدل ایک ایسی چیز ہے جس کو
مختلف معنوں میں سمجھ سکتے ہیں لیکن قرآن کریم نے قول کے عدل کے ہر پہلو کوکھول کر بیان فرمایا ہے.قول عدل کی پہلی خصوصیت:
قول کے لحاظ سے دنیا میں ہم بعض ایسے نظارے بھی دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ بہت
خوبصورت اور حسین باتیں کرتے ہیں اور ان کا قول بظاہر عدل پر مبنی ہوتا ہے.آج تمام دنیا میں جتنے
مذہبی، سیاسی یا سماجی لیڈر ہیں وہ عدل کی بات کر رہے ہیں اور ساری دنیا عدل کی باتوں سے بھری ہوئی
ہے.پھر وہ کیا بات ہے جو قرآن کریم نے پیش کی جو نئی اور اس سے مختلف ہے.ہر دنیا کا لیڈ ر خواہ وہ
مشرق سے تعلق رکھتا ہو، خواہ مغرب سے تعلق رکھتا ہو، خواہ اشترا کی فلسفہ سے تعلق رکھتا ہو، خواہ
استعماری فلسفہ سے تعلق رکھتا ہو جب بھی وہ بات کرتا ہے عدل کی ہی بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ دنیا
میں عدل قائم ہونا چاہئے ، اس کے سوا امن قائم نہیں ہوسکتا اور پھر بڑی حسین زبان استعمال کرتا ہے.قرآنی تعلیم کے مطابق ہر وہ شخص جو خدا کا حق ادا نہیں کرتاوہ اس کے بندوں کا بھی حق ادا نہیں کرسکتا.اس ضمن میں بانی سلسلہ احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام
فرماتے ہیں:
اخلاق دو قسم کے ہوتے ہیں ایک تو وہ جو آج کل کے نو تعلیم یافتہ پیش کرتے ہیں کہ
Page 236
224
عدل، احسان اور ایتاء ذی القربی - حصه چهارم
ملاقات وغیرہ میں زبان سے چاپلوسی اور مداہنہ سے پیش آتے ہیں اور دلوں میں نفاق اور کینہ بھرا ہوا
ہوتا ہے یہ اخلاق قرآن شریف کے خلاف ہیں.دوسری قسم اخلاق کی یہ ہے کہ سچی ہمدردی کرے
دل میں نفاق نہ ہو اور چاپلوسی اور مداہنہ وغیرہ سے کام نہ لے جیسے خدا تعالیٰ فرماتا ہے.إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَ اِيْتَائِ ذِي الْقُرْبى (56)
(النحل 91:16)
جو آیت حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے اقتباس میں پیش کی ہے یہ وہی ہے جو میرے
ان خطبات کا عنوان ہے یعنی اِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَ اِيْتَائِ ذِي الْقُرْبى
اس آیت میں درجہ بدرجہ اللہ تعالیٰ کے تین احکامات بیان کیئے گئے ہیں.پہلا یہ کہ جب بات کرو تو
انصاف سے کرو اور دوسرا یہ کہ انصاف ہی سے نہیں بلکہ ہمیشہ نرمی سے بات کرو اور تیسرا اس سے بھی
بڑھ کر یہ کہ جیسے تم اپنے بہت ہی عزیز رشتہ دار سے بات کرتے ہو جیسے ماں اپنے کسی پیارے بچے
سے گفتگو کر رہی ہو.جہاں تک پہلے درجہ یعنی عدل کا تعلق ہے اسکی سچائی کا امتحان قرآن کے نزدیک اس وقت
ہوتا ہے جب کسی کو اپنے کسی قریبی کے خلاف گواہی دینی پڑے جیسے کہ فرمایا: وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبى
قرآن کریم نے دوسری وضاحت قول عدل کی یہ فرمائی وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْ لی کہ وہ لوگ
جو عدل کی باتیں کرتے ہیں اگر وہ بچے ہیں تو انکی پہچان یہ ہے کہ جب ان کے قریبیوں کا معاملہ
در پیش ہو تو ان کے خلاف بھی کچی گواہی دینے کی طاقت اور قوت رکھتے ہوں لیکن آج آپ
دنیا والوں کو دیکھیں اور اس کسوٹی پر ان کو پرکھ کر دیکھیں تو دنیا میں جتنے بڑے بڑے عدل کا دعویٰ
کرنے والے ہیں ان کا یہ حال ہے کہ وہ عدل کا محدود اور نسبتی تصور رکھتے ہیں.جب اس قسم کے
اشتراکات بنائے جاتے ہیں ان کا انصاف کا تصور محض نسبتی ہوتا ہے.چنانچہ اگر مغربی بلاک کا کوئی
لیڈ ر عدل کی بات کرتا ہے تو جب اسکے بلاک اور اسکے تعلق رکھنے والے ممالک کے خلاف کوئی ظلم اور
ناانصافی کے بارہ میں احتجاج کرتا ہے تو وہ خاموش ہو جاتا ہے اور ان کے خلاف کوئی تنقید برداشت
نہیں کرتا اور اگر ان سب کا مشترکہ دشمن کوئی عدل کے خلاف اقدام کرے خواہ اسکی نا انصافی کسی اور
قوم سے ہی ہو تو اس وقت یہ سب مل کر اسکے خلاف شور مچاتے ہیں.بورژوا اور اشترا کی اتحادات پر
یہ بات برابر چسپاں ہوتی ہے.وہ لوگ جو فی الحیوۃ الدنيا عدل کی باتیں کرتے ہیں جب ان
کا اوپر بیان کردہ قرآنی کسوٹی پر امتحان لیا جائے تو اکثر غلط ثابت ہوتا ہے.
Page 237
قول
میں
عدل
225
آنحضرت ﷺ کی زندگی میں قول عدل کی مثالیں :
درجنوں مثالیں آنحضرت ﷺ کے ذاتی کردار کی دی جاسکتی ہیں اور ان خطابات کے
دوران دی بھی جاچکی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ہمیشہ کامل انصاف کا
سلوک فرمایا.بار ہا آپ نے ایک مسلمان کے خلاف ایک یہودی یا مشرک کے حق میں فیصلہ دیا
جب ان کو حق پر پایا.جہاں تک مالی معاملات میں آپ کے ذاتی کردار کا تعلق ہے آپنے ایک قرض دار کو نہ
صرف اس کا پورا قرض ادا کیا بلکہ ہمیشہ ان کے حق سے بڑھ کر عطا فرمایا.یہی تاکیدی تعلیم آپ نے
اپنے صحابہ کو دی.آپ کا یہ کردار محض مالی تنازعوں سے تعلق نہیں رکھتا بلکہ یہ آپ کا عمومی کردار تھا کہ
ہمیشہ دوسروں کو اپنے حق سے زیادہ دیا کرتے تھے اور محض انصاف نہیں بلکہ احسان کا سلوک فرمایا
کرتے تھے اور اسی کی آپ نے اپنے صحابہ کی سوسائٹی میں ترویج کی.بعض دفعہ آپکے مالی لین دین
میں احسان کا عصر تو محض احسان کے دائرہ سے نکل کر بلاشبہ ایتا ء ذالقربی کے دائرہ میں داخل
ہو جاتا تھا.اس کی ایک بہت ہی پیاری مثال مسند احمد بن حنبل سے روایت ہے کہ ایک دفعہ ایک غزوہ
سے واپس آتے ہوئے آپ نے دیکھا کہ ایک صحابی جابر بن عبد اللہ کا اونٹ بہت آہستہ چل رہا
تھا.رسول اللہ اللہ نے وجہ پوچھی تو اس نے عرض کیا کہ یہ لنگڑا رہا ہے.رسول اللہ ﷺ نے اپنے
کوڑے سے اسے ایک ہلکی سے ضرب لگائی تو وہ ایک اعلی درجہ کے صحت مند اونٹ کی طرح بہت
تیزی سے دوڑنے لگا.رسول اللہ ﷺ نے جابر سے پوچھا کہ کیا تم اس اونٹ کو میرے پاس بیچنا
پسند کرو گے؟ جابر نے عرض کیا یہ اونٹ آپ ہی کا ہے.اس کا کوئی معاوضہ نہیں لوں گا آپ نے
فرمایا نہیں.تمہیں لازماً اسکا معاوضہ لینا ہوگا اور ابھی طے کرو.اس پر حضرت جابر نے مجبوراً اس کا پورا
پورا معاوضہ طے کیا اور درخواست کی کہ اب اس اونٹ پر سواری کرنے کی اجازت دی جائے.آپ
نے بڑی بشاشت سے اسکو اجازت دی اور مدینہ پہنچ کر حکم دیا کہ اس اونٹ کی قیمت کے طور پر
میرے حساب میں اتنا سونا تول کر جابڑ کو دے دو.جب جابر کو قیمت دے دی گئی تو وہ اس اونٹ کو
چھوڑ کر پیدل ہی واپس جانے لگا.رسول اللہ ﷺ نے مسکرا کے فرمایا جابر ! اپنا اونٹ تو لے جاؤ.اس نے تعجب سے کہا کہ ابھی میں نے اس کی پوری قیمت وصول کی ہے.آپ نے فرمایا یہ اونٹ بھی
اور اس کی قیمت بھی تمہاری ہی ہے.(57)
Page 238
226
عدل، احسان اور ایتاء ذی القربى - حصه چهارم
دنیا کے پردہ پر آپکو اس قسم کے سودے کی مثال نظر نہیں آئے گی.ہاں بعض دفعہ ماں باپ
اپنے کسی پیارے بچے سے بظاہر اپنی ایک چیز خریدتے ہیں اور پھر قیمت ادا کرنے کے بعد وہ چیز بھی
اسے واپس کرتے ہیں.یہ خاص اظہار محبت کا سلوک صرف ایتا ء ذی القربی میں دکھائی دے گا.پس بلاشبہ حضرت اقدس رسول اللہ ﷺ کا مالی لین دین صرف کامل انصاف پر ہی مبنی نہیں ہوتا تھا
بلکہ اس سے بڑھ کر اس میں احسان اور ایتاء ذی القربی کے جلوے دکھائی دیتے ہیں.قول عدل کی دوسری خصوصیت :
قرآن کریم نے قول عدل کی ایک اور تفسیر بھی فرمائی ہے.فرمایا:
يَايُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (الاحزاب 71:33
اے وہ لوگو! جو ایمان لائے ہو تقوی اختیار کرو اور صاف اور سیدھی بات کہو.قول سدید سے مراد یہ ہے کہ ایسی بات جس میں کو ئی بھی غلط جھکاؤ نہ ہو، عین درست بات ہو
اور اس میں قطعاً کسی قسم کی کوئی بھی نہ ہو.بسا اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ ایک بات بچی تو ہوتی ہے اس
میں اس کے باوجود بل پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور بات سچی ہوتے ہوئے بھی کسی دوسرے کو دھو کہ
میں مبتلا کر سکتی ہے پس آنحضرت ﷺ کو خدا تعالیٰ نے جو تعلیم سکھائی وہ یہ تھی کہ محض سچ قول عدل
نہیں ہے.ایسا صاف ستھرا سچ بولو کہ مخاطب کیلئے کسی قسم کی کوئی غلط فہمی کا سوال باقی نہ رہے لیکن اس
کے ساتھ ایک اور بھی خطرہ سے متنبہ فرما دیا.بعض لوگ قول عدل کا مطلب یہ لے لیتے ہیں کہ کسی
مخالف سے سچ کے نام پر سختی سے بات کی جائے جس بات کو وہ سچا سمجھتے ہیں اسے منہ پر مارا جائے.قرآن کریم جس قول کو قولِ عدل کہتا ہے اس میں منہ پر مارنے والا کوئی تصور موجود نہیں بلکہ
خود اس غلطی کی اصلاح فرماتا ہے.چنانچہ فرمایا.إِذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى فَقُوْلَا لَهُ قَوْلًا لَّيْنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَرُ
(45-44:20)
أوْ يَخْشُى
کہ اے موسیٰ اور ہارون تم فرعون کے دربار میں جانے والے ہو سچ تو تم بہر حال کہو گے
قول سدید سے کام لو گے اور اس میں کوئی شک نہیں لیکن قول لینا یعنی نرم بھی ہونا چاہئے اور قول کا
بچے اور سیدھے ہونے کے علاوہ نرم ہونا احسان سے تعلق رکھتا ہے.قول سدید کے ساتھ لینا کو
ملا کر اسکی تلخی کو دور فرما دیا.
Page 239
قول
عدل
میں
227
قول عدل کی تیسری خصوصیت :
پھر قول کے عدل میں ایک مزید حسن پیدا فرما دیا اور صرف قول کے عدل کی بات نہیں کی بلکہ
اس کو مزید حسین بنانے کی بھی تعلیم دی.فرمایا.وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ
إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ( حم السجدہ 34:41)
اور بات کہنے میں اس سے بہتر کون ہوسکتا ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک
اعمال بجالائے اور کہے کہ میں یقیناً کامل فرمانبرداروں میں سے ہوں.اس آیت میں دو باتیں بیان فرمائیں.اول یہ کہ سب سے اچھی بات کی طرف بلانے سے
قول میں حسن پیدا ہو جاتا ہے جتنی زیادہ اچھی بات کی طرف تم بلاؤ گے اتنا زیادہ تمہارا قول حسین
ہوتا چلا جائے گا.پس اللہ سے بہتر اور کیا چیز ہوسکتی ہے جسکی طرف بلایا جارہا ہو.خدا کی طرف
بلانے والے سب سے بچے اور سب سے زیادہ حسین بات کرنے والے ہیں لیکن ایک شرط کے
ساتھ کہ ان کا عمل بھی اس سچی بات پر ہونا چاہیے ورنہ قول حسین نہیں ہوسکتا.ویسے تو ہر آدمی کہہ سکتا
ہے کہ دنیا میں لاکھوں کروڑوں ایسے ہیں جو خدا کی طرف بلاتے ہیں پس ان کا قول بھی تو قول حسن
ہوگا.وہ کیا فرق ہے کہ جس کو اسلام نے ہمیں سکھایا ہے؟ فرمایا فرق یہ ہے کہ اچھی بات کی طرف
بلانے والا اس پر عمل بھی کرتا ہو.یہ نہ ہو کہ خدا کی طرف بلانے والا ہو اور شیطان کی صفات اس سے
ظاہر ہورہی ہوں.پس قرآن کریم نے جو تعلیم دی ہے اسے خوب کھول کھول کر بیان کیا اور اس میں
ایک نہایت حسین توازن پیش فرما دیا اور یہ تو ازن خود عدل کی علامت ہے.قول عدل کی چوتھی خصوصیت:
پھر قول عدل کے نتیجہ میں معاشرہ کی اصلاح کا راز سکھایا.فرمایا:
ط
يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ
أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا
اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو! اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور صاف سیدھی بات
(الاحزاب 71:33-72)
کیا کرو.وہ تمہارے لئے تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا اور تمہارے
Page 240
228
عدل، احسان اور ایتاء ذی القربی - حصه چهارم
گناہوں کو بخش دے گا اور جو بھی اللہ اور اسکے رسول کی اطاعت کرے تو یقیناً
اس نے ایک بڑی کامیابی کو پالیا.فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے اعمال کی اصلاح ہو تو قولِ سدید یا دوسرے لفظوں میں
قول عدل اختیار کرو.اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم اپنے اعمال اور معاشرہ کی اصلاح چاہتے ہو تو
قول سدید انتہائی ضروری ہے.اس کے نتیجہ میں نہ صرف تمہارے اعمال اصلاح پذیر ہو جائیں گے
بلکہ تمہاری سابقہ غلطیاں بھی معاف کی جائیں گی.سب سے اونچا مقام جس کا ایسے لوگوں کو وعدہ دیا
گیا ہے یہ ہے کہ جو بھی ایسا کرے گا اور اللہ کے رسول کے احکامات اور اعمال کی پیروی کرے گا
اسے بہت عظیم کامیابی عطا کی جائے گی.اب قول عدل کے اس مضمون کو خوب سمجھنے کے بعد ہم اس مضمون
کا نسبتاً زیادہ تفصیل سے
مطالعہ کرتے ہیں کہ بین الاقوامی تعلقات میں اسلام نے عدل کی کیا تعلیم دی ہے.
Page 241
بنی نوع انسان کے مابین قیام عدل کا بنیادی اصول
23- بنی نوع انسان کے مابین قیامِ عدل کا بنیادی اصول
فرمایا.ياَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِنْ ذَكَرٍو انْثَى وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا
وقَبَابِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَكُمْ إِنَّ اللهَ
(الحجرات 14:49)
عَلِيمٌ خَبِيرٌ
اے لوگو! ہم نے تم کو مرد اور عورت سے پیدا کیا اور تم کو کئی گروہوں اور قبائل
میں تقسیم کر دیا ہے تا کہ تم ایک دوسرے کو پہچانو.اللہ کے نزدیک تم میں سے
زیادہ معزز وہی ہے جو سب سے یادہ متقی ہے.اللہ یقیناً بہت علم رکھنے
229
والا (اور ) بہت خبر رکھنے والا ہے.آج کی دنیا میں جتنے فسادات ہیں اور انسان کو انسان سے جتنے خطرات لاحق ہیں ان میں
جو بھی محرکات کارفرما ہیں، ان میں قومی برتری کا احساس سب سے طاقتور اور خطرناک محرک ہے.اسکو Racialisml Racism کہا جاتا ہے.یہ Racism اگر چہ بظاہر نا پسند کیا جاتا ہے
لیکن آج بھی اسی طرح موجود ہے جس طرح نازی دور میں جرمنی میں ہوا کرتا تھا.یہ
Racism سفید بھی ہے اور سیاہ بھی.اور سفید قوموں کے خلاف جو افریقن ممالک میں نفرتوں کے
لاوے ابلتے رہتے ہیں، اس کو Black یا سیاہ فام Racism کہا جاسکتا ہے.افسوس ہے کہ اب
تک دنیا اس بھوت کے چنگل سے آزاد نہیں ہو سکی.یہ کوئی ایسا پودا نہیں ہے جسے آسانی سے اکھاڑ کر پھینک دیا جائے لیکن سب اہل حق جو سچ
بات کو دیکھنا اور پہچانا جانتے ہیں ان کو علم ہے کہ باوجود ہر قسم کی تقریروں اور Racism کے خلاف
باتوں کے جگہ جگہ Racism کی جڑیں مختلف شکلوں میں مغرب کے تمام ممالک میں بھی پائی جاتی
ہیں اور مشرق کے تمام ممالک میں بھی پائی جاتی ہیں.کوئی دنیا کا خطہ ایسا نہیں جہاں نہ پائی جاتی
ہوں.یہ ایسا زہر اور سخت جان پودا ہے کہ یہ معاشروں میں نہیں، فلسفوں میں بھی بڑی خاموشی کے
ساتھ داخل ہو جاتا ہے.وہ ماہرین جو گہری نظر سے مغرب اور سفید فام روس اور چین کے تعلقات کا
مطالعہ کرتے ہیں، خوب جانتے ہیں کہ دونوں مغرب اور سفید فام روس سفید Racism
کو اشتراکیت پر ترجیح دیں گے اگر اشتراکیت کے پھیلاؤ کے ساتھ زرد فام چین اس دنیا پر غالب آ جاتا
Page 242
230
عدل، احسان اور ایتاء ذی القربى - حصه چهارم
ہے.دونوں ہی اپنی سفید فام برتری کو اس بات پر ترجیح دیں گے کہ اشتراکیت زرد فام چین سے متعلق
ہو کر دنیا پر غالب آئے.کسی قیمت پر بھی وہ زرد فام چین کا دنیا پر غلبہ برداشت نہیں کر سکتے.قرآن کریم کے نزدیک نسل پرستی کی ہر شکل کو دنیا سے نابود کرنا ہوگا.اس کے بغیر دنیا میں
امن قائم کرنا ناممکن ہے.قرآن کریم کی جو آیت ہم نے اس ضمن میں پیش کی ہے اسکے مطابق
باوجود اس کے کہ رنگ اور قومیتیں مختلف ہیں مگر سب انسان بہر حال ایک ہی ماں باپ کی نسل سے
منسلک ہیں.رنگ اور نسل کی تفریق ان کی برتری ظاہر کرنے کیلئے نہیں بلکہ ان کی پہچان کی خاطر
ہے.اگر انسان دوسرے انسان پر برتری حاصل کرنا چاہتا ہے تو صرف تقویٰ کے ذریعہ حاصل ہو سکتی
ہے.کیونکہ ایک متقی انسان ہر دوسرے انسان کو اپنے برابر سمجھتا ہے.بلکہ جتنا زیادہ متقی ہوگا اپنے
آپ کو اور بھی دوسرے سے کمتر سمجھے گا.مندرجہ بالا استنباط ہم نے اس آیت سے اخذ کیا ہے.فرمایا:
يَايُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِنْ ذَكَرِ وانْثَى وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا
وَقَبَابِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقُكُمْ إِنَّ اللَّهَ
عَلِيمٌ خَبِيرٌ
(الحجرات 14:49)
ہم نے تو تمہیں اس لئے قوموں میں اور فرقوں میں اور مختلف قبیلوں میں تقسیم
کیا تھا تا کہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو اور یہ تمہاری پہچان کا ذریعہ بن جائیں
ہرگز ان باتوں میں کوئی عزت نہیں ہے.عزت اللہ کا تقویٰ اختیار کرنے میں
ہے.پس تم میں سے سب سے زیادہ معزز وہی ہے جو سب سے زیادہ خدا کا
خوف رکھتا ہے.نسلی برابری کا ایک عظیم الشان چارٹر :
آنحضرت ﷺ نے اس مضمون کو حجتہ الوداع پر بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ بیان فرمایا.آنحضرت می فرماتے ہیں:
يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ وَّإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌاَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِي
عَلَى أَعْجَمِي وَلَا لِعَجَمِي عَلَى عَرَبِيِّ.وَلَا لَا حُمَرَ عَلَى أَسْوَدَ وَلَا
Page 243
بنی نوع انسان کے مابین قیام عدل کا بنیادی اصول
لاسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إِلَّا بِالتَّقْوى اَبَلَّغْتُ قَالُوا قَدْ بَلَّعَ رَسُول اللَّهِ
صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلم
”اے لوگو! تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک تھا پس ہوشیار ہو کر سن لو
کہ عربوں کو عجمیوں پر کوئی فضیلت حاصل نہیں اور نہ عجمیوں کو عربوں پر کوئی
فضیلت ہے.اسی طرح سرخ و سفید رنگ والے کو کالے رنگ والے لوگوں پر
کوئی فضیلت نہیں اور کالے رنگ والے کو گوروں پر کوئی فضیلت نہیں ہے.(ہاں جو بھی ان میں سے اپنی ذاتی نیکی سے آگے نکل جائے وہی افضل ہے.)
لوگو بتاؤ کیا میں نے تمہیں خدا کا پیغام پہنچا دیا ہے؟ سب نے عرض کیا بے شک
خدا کے رسول نے اپنی رسالت پہنچادی ہے
Racialism کی بیماری کی جڑ :
(58)،،
231
Racialism جو قوموں کے درمیان تفریق کی بنیادی وجہ ہے دراصل ہر گھر میں پرورش پا رہا
ہے.قرآن کریم چونکہ خدا تعالیٰ کا کلام ہے اس لئے اس میں اس نے بیماری کی جڑ کو پکڑا اور تفصیل
سے اس پر روشنی ڈالی.Racialism سے بچاؤ کیلئے قرآن کریم کی حکیمانہ تعلیم :
فرمایا:
يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا
خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاء مِنْ نِّسَاءِ عَلَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا
تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ
بَعْدَ الْإِيْمَانِ ۚ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَيكَ هُمُ الظَّلِمُونَ )
(الحجرات 12:49)
اے لوگو جو ایمان لائے ہو! ( تم میں سے ) کوئی قوم کسی قوم پر تمسخر نہ کرے.ممکن ہے وہ ان سے بہتر ہو جائیں اور نہ عورتیں عورتوں سے ( تمسخر کریں
ہوسکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو جائیں اور اپنے لوگوں پر عیب مت لگایا کرو اور
Page 244
232
عدل، احسان اور ایتاء ذی القربى - حصه چهارم
ایک دوسرے کو نام بگاڑ کر نہ پکارا کرو.ایمان کے بعد فسوق کا داغ لگ جانا
بہت بری بات ہے اور جس نے تو یہ نہ کی تو یہی وہ لوگ ہیں جو ظالم ہیں.اب یہ مضمون اتنا کھول کر بیان کر دیا گیا ہے کہ کوئی انسان جو سرسری طور پر بھی قرآن کریم
کا مطالعہ کرے وہ یہ عذر نہیں پیش کر سکتا کہ مجھے اس تفصیلی تعلیم کا علم نہیں تھا.مگر وہ تمام ممالک جن
میں قرآن کریم کی یہ ہدایات بار بار پڑھی جاتی ہیں ان میں بھی یہ خرابیاں موجود ہیں.بظاہر آمــنــا
وصدقنا ضرور کہتے ہیں لیکن عمل کی دنیا میں اس عہد کو بالکل بھلا دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ معمولی
باتیں ہیں لیکن یہی معمولی باتیں ہیں جن سے نہایت خطرناک فتنے اٹھتے ہیں اب دیکھیں
ہندو پاکستان میں قومی لطیفوں کا بہت رواج ہے.کوئی جلا ہوں نائیوں اور دیگر پیشہ وروں کے خلاف
غیر پیشہ وروں نے لطیفے بنائے ہوئے ہیں اور زمینداروں کے خلاف پیشہ وروں نے لطیفے بنائے
ہوئے ہیں.اسی طرح پاکستان میں سکھوں کے خلاف اور ہندوستان میں مسلمانوں کے خلاف لطیفے
بنا کر مشتہر کئے جاتے ہیں.ان لطائف کو اگر ایسے موقع پر استعمال کیا جائے جبکہ کسی کی دل آزاری
نہ ہو تو پھر تو کچھ بات بھی ہو.ان لطیفوں کے رد عمل کی وجہ سے مختلف قوموں میں Racialism
پروان چڑھتا ہے.قرآن کریم نے تنبیہ فرمائی تھی کہ دیکھو ایسانہ کر دور نہ تقدیر ان باتوں کو الٹادے گی جن کو تم
آج ذلیل اور ادنی سمجھتے ہو وہ ہو سکتا ہے تم پر غالب آجائیں.چنانچہ یہ عمل دنیا کی ہر سوسائٹی میں اسی
طرح رونما ہوا ہے.ایک زمانہ تھا کہ جب انگلستان میں بھی پیشہ وروں اور تاجروں
کو تحقیر اور تذلیل کی
نظر سے دیکھا جاتا تھا.صرف ایک Landed Gentry تھی وہ اس ملک کے چودھری تھے اور
سمجھتے تھے کہ ہر دوسرا کمین ہے.دیکھئے خدا کی تقدیر نے کس طرح زمانہ کو پلٹا دیا ہے.آج وہ
سارے تاجر تمام سوسائٹی پر چھائے ہوئے ہیں اور سب سے زیادہ معزز بنے ہوئے ہیں.آنحضرت ﷺ کا طریق تربیت:
اب میں آنحضرت ﷺ کے گھر میں قول عدل سے متعلق آپ کی تربیت کی مثالیں پیش
کرتا ہوں.حضرت خدیجہ کے بعد آپ کو جس زوجہ مطہرہ سے سب سے زیادہ پیار تھاوہ حضرت عائشہ
صدیقہ تھیں.جب آپ نے حضرت عائشہ میں ایک ایسی بات دیکھی جو آپ کے اعلیٰ معیار کے
مطابق قول عدل کے خلاف تھی تو آپ نے وہیں پرسش فرمائی اور کس طریق سے پرسش فرمائی یہ ایک
Page 245
بنی نوع انسان کے مابین قیام عدل کا بنیادی اصول
233
(59)
بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے.حضرت عائشہ خود ہی بیان کرتی ہیں کہ میں نے حضور اکرم سے
کہا آپ صفیہ کا بہت خیال کرتے ہیں مگر وہ ایسی ہے یعنی اپنی چھوٹی انگلی کھڑی کر دی اور اس طرح
حضرت صفیہ کے چھوٹے قد پر طنز کر دیا.آپ نے فرمایا عائشہ ! تم نے ایک ایسی بات کہی ہے کہ اگر
اسے سمندر کے پانی میں ملا دیا جائے تو اس کا ذائقہ تبدیل ہو جائے ، اس کا مزاج بدل جائے.اب
دیکھیں کتنی عظیم بات ہے اور کتنی گہری بات ہے.اس خیال سے حضرت عائشہ نے ایک
دوسری زوجہ مطہرہ کے متعلق طبعی فطری رقابت کے نتیجہ میں جس طرح بات کہہ دی آپ نے اس کو نظر
انداز نہیں فرما دیا لیکن بات ایسی کہی جو عین اس کا جواب تھی اور ایسا عمدہ جواب کہ اس سے بہتر
جواب متصوّ رہی نہیں ہوسکتا.بین الاقوامی جھگڑوں کے فیصلہ کیلئے قرآن کی عادلانہ تعلیم :
آپ نے ہمیں قول میں عدل کے نمونے بتائے اور قول میں حسن کی تعلیم دی یہ وہ بنیادی باتیں
ہیں جن پر قائم ہوئے بغیر دنیا سے فسادات نہیں مٹ سکتے.یہ حقیقت ہے کہ انسانی فطرت کے اندر
جو بنیادی بیماریاں پائی جاتی ہیں جب تک ان کی اصلاح نہ ہو ان کے نتیجہ میں پیدا ہونے والے مفاسد
سے انسان کبھی نہیں بچ سکتا.محض ہتھیاروں کی موجودگی کی وجہ سے انسان خطرہ میں نہیں ہے.اگر
انسان خطرہ میں ہے تو ان ہتھیاروں کے مالک قوموں کی ذہنیت کے فساد کی وجہ سے خطرہ میں ہے.اب دیکھتے ہیں کہ اگر یہ اصلاح نہ ہوئی ہو اور قو میں آپس میں لڑ پڑیں تو پھر کیا طریق اختیار کرنا
چاہیے اور قرآن کریم کے نزدیک بین الاقوامی جھگڑوں کو طے کرنے کیلئے عادلانہ تعلیم کیا ہے.فرمایا:
وَإِنْ طَابِفَتْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوْا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۚ فَإِنْ
بَغَتْ إِحْدهُمَا عَلَى الْأخْرى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ
إلَى أَمْرِ اللهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا
إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ
(الحجرات 10:49)
اور اگر مومنوں میں سے دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح
کرواؤ.پس اگر ان میں سے ایک دوسری کے خلاف سرکشی کرے تو جو زیادتی
کر رہی ہے اس سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے فیصلہ کی طرف لوٹ آئے.پس اگر وہ لوٹ آئے تو ان دونوں کے درمیان عدل سے صلح کرواؤ اور انصاف
کرو.یقینا اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے.
Page 246
234
عدل، احسان اور ایتاء ذی القربى - حصه چهارم
یہاں سب سے پہلے تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ یہاں مومنوں کی بات کی گئی ہے، عام بنی نوع
انسان کی بات نہیں کی گئی.اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم جو یہ تعلیم دیتا ہے اس پر مومنوں نے ہی تو
عمل کرنا ہے باقی جو قرآن کریم کا انکار کرتے ہیں وہ کیوں عمل کریں گے لیکن اگر مومن عمل کریں تو
وہ ایک نمونہ بن کر لوگوں کے سامنے ابھر سکتے ہیں پس قرآن کریم کی تعلیم مومنوں کے آئینہ میں
غیروں کیلئے ایک نہایت حسین تصویر بناتی ہے.قرآن کریم فرماتا ہے لڑائی کا انتظار نہیں کرنا لڑائی
سے پہلے اصلاح احوال کر اور نہ پھر بہت دیر ہو جائے گی پھر تم اس قابل نہیں رہو گے کہ لڑائی کو روک
سکو لیکن اگر تمہارے اصلاح کروانے کے باوجود یا صلح کی کوششوں کے باوجود دوفریق آپس میں
لڑ پڑیں تو پھر نصیحت کی بات نہیں کرنی محض ریزولیوشنز کی بات نہیں کرنی پھر تم سب کو متحد ہو کر اس
ایک فریق کے خلاف تلوار اٹھانی پڑے گی جو تمہارے سب کے نزدیک غلطی پر ہے یا جس نے زیادتی
کی ہے پھر فرمایا یہ کرنے کے بعد جب صلح ہو جائے امن پیدا ہو جائے اس کے بعد پھر جب تم فیصلے
کرو گے تو اس میں انصاف سے کام لینا اگر اس وقت تم نے انصاف سے کام نہ لیا تو آئندہ مزید
جنگوں کے بیج بودو گے.قرآنی تعلیم کی خلاف ورزی کے نتیجہ میں آئندہ جنگوں کا خطرہ:
گزشتہ جنگ عظیم کے بعد دنیا کی بڑی طاقتوں نے جس طرح سر جوڑے اور جس طرح
مجرم قوموں کو جن کو وہ مجرم سمجھتے تھے، سزادی اور اس نیت سے سزادی کہ ان کو چل کے رکھ دیں ان
کے فیصلوں میں بہت سی خلاف انصاف باتیں موجود تھیں اور دوسری جنگِ عظیم کی بنیاد ان فیصلوں
نے ڈال دی تھی جو پہلی جنگ عظیم کی صلح کے بعد ہوئے.ہر طالب علم جو گہری نظر سے تاریخ کا
مطالعہ کرتا ہے اس بات کی تصدیق کرے گا.وہ آسانی سے ان تمام ظالمانہ فیصلوں کی نشاندہی کر سکتا
ہے جن کے رد عمل کے طور پر مغرور قوموں نے دوبارہ سر اٹھایا اور انتقام لینے کی کوشش کی.اور گزشتہ
جنگ میں جنگ کے رکنے کے بعد جو فیصلے کئے گئے ہیں ان میں بھی آئندہ جنگ کے لئے بنیادیں
قائم کر دی گئی ہیں.دوسرے فیصلوں کو چھوڑئیے جرمن قوم کو تقسیم کر دیا گیا ہے.جرمن قوم کو یہ سمجھ کر
تقسیم کر دیا گیا ہے کہ ایک ایسی قوم ہے کہ جس سے ہمیشہ ہمیں خطرہ رہے گا جب بھی اس قوم کو
سراٹھانے کا موقع ملے گا اس نے دوبارہ پھر پہلی باتوں کو دہرانا ہے اور دوبارہ ہم سب کیلئے خطرہ بن
جائے گی اس لئے چرچل نے اور روز ویلٹ اور سٹالن نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ اس کو اس طرح بیچ میں
سے کاٹ دو اور اس طرح مختلف Ideologies کے سپرد کر دو کہ جرمن قوم ہمیشہ ایک دوسرے
Page 247
بنی نوع انسان کے مابین قیام عدل کا بنیادی اصول
235
کیلئے خطرہ بنی رہے اس طرح جرمنی کی توجہ باہر کی قوموں کی طرف سے ہٹ جائیگی اور اگر کبھی یہ مواد
پھوٹا تو ایک دوسرے کے خلاف پھوٹے گا.کیونکہ دنیا میں نظریاتی تبدیلیاں واقع ہو رہی ہیں
اور ہوتی چلی جائیں گی.اگر آئندہ مشرق اور مغرب کا اتحاد ہو جائے تو یہ ہر گز بعید نہیں اور اس
صورت میں جرمنی پہلے سے زیادہ عظیم طاقت بن کر ابھرے گا.صرف یہ ایک فیصلہ نہیں، ایسے اور فیصلے بھی ہوئے ہیں جن کے نتیجہ میں جنگ کا خطرہ ٹالا
نہیں جاسکتا.پس قرآن کریم یہ کہہ کر ختم نہیں کر دیتا کہ اگر تم لڑو اور زیادتی کرنے والے ملک کو
شکست دے دو تو بات ختم ہو جائے گی.فرمایا ہر گز نہیں جب تم ایک ظالم قوم پر غالب آ جاتے ہو وہ
وقت ہے کہ تم انصاف سے کام لو اور اس ظالم قوم کے خلاف بھی زیادتی نہ کرو.پھر تم یقین جانو کہ
تمہیں ایک مستقل امن کی ضمانت دی جاسکتی ہے.فرمایا:
اِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ
اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے.اس کا مطلب ہے کہ خدا کا قانون ہے جو تمہارا ساتھ دیگا.جن قوموں سے اللہ محبت کیا کرتا
ہے ان کو آپس میں لڑایا نہیں کرتا.بلا امتیاز تمام بنی نوع انسان کے معاملات میں نیکی کی قرآنی تعلیم :
جہاں تک مسلمانوں کے اس دور کا تعلق ہے جب خود مسلمان غیروں سے
نبرد آزما تھے یعنی
جب غیر قومیں ان پر حملہ کر رہی تھیں جب مشرکین مکہ خصوصیت کے ساتھ آنحضرت ﷺ اور
آپ کے غلاموں کو صفحہ ہستی سے مٹادینے کے درپے تھے اس دور میں قرآن کریم نے جو تعلیم دی ہے
یہ وہ تعلیم ہے جس سے خوب اچھی طرح روشن ہو جاتا ہے کہ یہ تعلیم کسی بندہ کی نہیں جس نے اپنے
جذبات کے نتیجہ میں وہ تعلیم دی ہو بلکہ ایک عالم الغیب والشہادۃ خدا کی تعلیم ہے جو اپنے سب
بندوں میں مشترک ہے.جس طرح حضرت بانی سلسلہ احمدیہ نے ایک بڑے نکتہ کی بات بیان فرمائی
که یا درکھنا کہ خدا کی کسی بندے سے رشتہ داری نہیں ہے.اگر ہے تو سب سے ہے.اگر نہیں تو کسی
سے بھی نہیں.پس اس معاملہ میں اگر محمد رسول اللہ کے اسوہ کو جانچنا ہے تو اس کے جانچنے کا وہ موقع
ہے جبکہ مسلمان اپنی بقا کی جنگ میں مبتلا تھے.دیکھنا چاہیے کہ اس وقت آنحضرت ﷺ پر نازل
ہونے والی تعلیم کیا تھی.فرمایا:
Page 248
236
عدل، احسان اور ایتاء ذی القربى - حصه چهارم
لَا يَنْصُكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ
يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ
يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ.(9:60)
یعنی اللہ تمہیں ان سے منع نہیں کرتا جنہوں نے تم سے دین کے معاملہ میں قتال
نہیں کیا اور نہ تمہیں بے وطن کیا کہ تم ان سے نیکی کرو اور ان سے انصاف کے
ساتھ پیش آؤ.یقینا اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے.فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہرگز اس بات سے نہیں روکتا کہ صرف ان لوگوں سے اپنا بدلہ لو جنہوں
نے تم سے دینی اختلافات کی بناء پر قتال کیا اور تمہیں اپنے گھروں سے نکالا.جنہوں نے یہ نہیں کیا
ان کے ساتھ انصاف سے کام لو اور نیکی سے کام لو.پھر فرمایا:
وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِاَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا
بَيْنَ النَّاسِ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (البقرة225:2)
ترجمہ: اور اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ اس غرض سے نہ بناؤ کہ تم نیکی کرنے یا تقویٰ
اختیار کرنے یا لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے سے بچ جاؤ اور اللہ بہت سننے
والا ( اور ) دائمی علم رکھنے والا ہے.یہاں یہ فرمایا گیا ہے کہ اے لوگو! نیکی کے نامپر
ظلم نہیں کرنا.اللہ کی قسمیں کھا کھا کر، یہ کہہ کر
کہ اللہ کا دین ہے اور اللہ کے دین کے تقاضے یہ ہیں کہ ہم تم پر زیادتی نہ کریں.ہرگز ایسا نہ کرنا.خدا
ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ خدا کو اپنی قسموں کا نشانہ بنالو اور پھر یہ کہو کہ خدا سے تعلق کے
تقاضے یہ ہیں کہ ہم تمہیں مٹادیں اور تم سے ہر قسم کی نیکی سے ہاتھ روک لیں.فرمایا ہرگز ایسا نہیں.خدا تعالیٰ کے ساتھ اگر تعلق ہے تو تمہیں تمام بنی نوع انسان سے ہمیشہ نیکی کرنی پڑے گی.
Page 249
رشتہ داروں کے متعلق عدل و احسان کی تعلیم
24 رشتہ داروں کے متعلق عدل و احسان کی تعلیم
237
یہ تو بین الاقوامی تعلقات کی بات تھی اب میں اندرونی طور پر تقسیم کے لحاظ سے قرآن کریم کے
عائد کردہ حقوق اور فرائض کی بات کرتا ہوں.یہ حقوق ماں باپ کے بچوں پر.بچوں کے ماں باپ
پر، بہن بھائیوں کے ایک دوسرے پر قریبی رشتہ داروں کے آپس میں ایک دوسرے سے تعلقات
کے مضمون پر مشتمل ہیں.والدین کے بچوں پر حقوق:
سب سے پہلے والدین کے حقوق کی بات ہے.والدین کے ساتھ احسان کا تاکیدی حکم:
اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے:
وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهُنَّا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَلُهُ
فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى الْمَصِيرُ (لقمان 15:31)
ترجمہ: اور ہم نے انسان کو اسکے والدین کے حق میں تاکیدی نصیحت کی.اس کی
ماں نے اسے کمزوری پر کمزوری میں اٹھائے رکھا اور اس کا دودھ چھڑانا دوسال
میں (مکمل ) ہوا.(اسے ہم نے یہ تاکیدی نصیحت کی ) کہ میرا شکر ادا کر اور
اپنے والدین کا بھی.میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے.اس ضمن میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ آنحضور ﷺ نے فرمایا خاک آلودہ ہو اس کی
ناک ، خاک آلودہ ہو اس کی ناک، خاک آلودہ ہو اس کی ناک ( تین دفعہ یہ الفاظ دہرائے ) یہ عربی
محاورہ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رسوا ہو گیا وہ ذلیل ہو گیا جس نے ایسی بات کی ،صحابہ نے عرض
کیا یا رسول اللہ ! کون ہے وہ شخص؟ کس کی بات فرمارہے ہیں.جس کی آپ مذمت کر رہے ہیں؟
فرمایا بہت ہی قابل مذمت اور بدقسمت ہے جس نے بوڑھے ماں باپ
کو پایا اور پھر ان کی خدمت
کر کے جنت میں داخل نہ ہوسکا.(60)
یہ بات بظاہر چھوٹی سی ہے لیکن آج اگر آپ انسانی معاشرہ پر نظر ڈال کر دیکھیں مغرب میں
بھی اور مشرق میں بھی بچے اپنے والدین کے حقوق ادا کرنے سے دن بہ دن غافل ہوتے چلے
Page 250
238
عدل، احسان اور ایتاء ذی القربی - حصه چهارم
جار ہے ہیں.یہ بات مغرب میں زیادہ ہے اور مشرق میں نسبتا کم.مگر مشرق میں بھی پھیلتی چلی
جارہی ہے اور اسکے نتیجہ میں بہت ہی خوفناک دکھ معاشرے میں پھیل گئے ہیں لیکن آنحضرت ملے
نے قرآنی تعلیم کے مطابق بار بار اپنے صحابہ کو ماں باپ کے حقوق کی طرف متوجہ فرمایا ، ان کے حقوق
کو واضح کیا اور ایسا احترام دلوں میں پیدا کر دیا جس کے نتیجہ میں ایک نہایت ہی حسین معاشرہ دنیا
کے سامنے ابھرا.ایک دفعہ ایک اعرابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی کرخت آواز میں جیسا کہ صحرائی
لوگوں کی بات کرنے کی عادت تھی.عرض کیا یا رسول اللہ ! میرا باپ میرا مال بٹورنا چاہتا ہے.آنحضور نے اس کو ویسا ہی جواب دیا مگر ویسے کرخت الفاظ میں نہیں مگر جس طرح اس کے دل میں
ایک سختی اور شدت پائی جاتی تھی اس کا علاج اس کو یہ بتایا کہ جاتو اور تیرا مال تیرے والد کی ملکیت ہے
اور تمہاری اولادوں کے اموال بھی تمہاری کمائی ہیں مزے سے اسے کھاؤ.(1
باپ کے متعلق کوئی بیٹا یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ میرا مال بٹور رہا ہے.امر واقعہ یہ ہے کہ والد کو
یہ اجازت ہے کہ وہ اپنے بیٹے کی کمائی میں سے اس طرح کھائے ، اس طرح اسے استعمال کرے
جیسے وہ اس کی ہے.لیکن بیٹے کو یہ اجازت نہیں دی کہ وہ والد کی کمائی سے اس طرح کا سلوک
کرے.اب بظاہر یہ بات عدل کے خلاف ہے لیکن آپ ذرا سا غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ بعینم
اسی طرح ہونا چاہیے تھا.باپ بیٹے سے جو محبت رکھتا ہے بیٹا باپ سے ویسی محبت فطرتا نہیں رکھ
سکتا.کیونکہ باپ کا مستقبل ہے بیٹا اور باپ بیٹے کا ماضی ہے اور بہت جلد بیٹے کا مستقبل اپنی اولاد
اور اپنی بیوی بچوں کی صورت میں ظاہر ہو جاتا ہے.یہ ایک ایسی انسانی فطرت کی بات ہے جو آج
دنیا میں ہر جگہ اس طرح آپ کو دکھائی دے گی کہ کوئی معقول اور سچائی پسند انسان اس سے انکار نہیں
کرسکتا.یقیناً اس اصول میں استثناء پائی جاتی ہے لیکن استثناء تو اصول کو ثابت کیا کرتی ہے.پھر باپ تو ایک ہوا کرتا ہے اور بیٹے کئی.اگر ہر بیٹے کو حق دے دیا جائے کہ باپ کی دولت
پر اس طرح چڑھ دوڑے گویا کہ اس کی ہے، تو فساد عظیم برپا ہو جائے.دیکھئے قرآن کریم کیسی فطرت
کی تعلیم ہے اور آنحضرت ﷺ نے اس کو اسی طرح سمجھا کر بیان فرمایا.باپ کا بیٹے کی کمائی میں حق
ہے اور اگر ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو ان کو بیٹے جو کچھ پیش کریں وہ صدقہ کے رنگ میں نہیں.یہ
نہ سمجھیں کہ وہ کوئی احسان کر رہے ہیں.ایک روایت میں آتا ہے کہ آنحضور ﷺ کی خدمت میں ایک بیٹا حاضر ہوا اور اس نے
Page 251
رشتہ داروں کے متعلق عدل و احسان کی تعلیم
239
اپنے باپ کے خلاف باتیں کیں اور کہا کہ میرا باپ ایسا ویسا ہے اور میری ساری جائیداد کو اپنے
تصرف میں لا رہا ہے.باپ بھی وہیں موجود تھا.بیٹے نے کہا یا رسول اللہ ! اس کو منع فرما ئیں میرے
معاملات میں دخل نہ دیا کرے.باپ خاموش رہا.ایک لفظ نہیں بولا.آنحضور ﷺ نے اس کی
آنکھوں میں غم دیکھا اور اس سے پوچھا کہ بات کرو، اپنے دل کی بات تو بتاؤ کہ کیا کہتے ہو.اس نے
عربی کے کچھ اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے کہ یا رسول اللہ ! جب یہ بچہ تھا اور اس کی ٹانگوں میں
طاقت نہیں تھی کہ یہ چل سکے میں نے اس کو گودیوں میں اٹھایا اور گودیوں میں اٹھا کر جگہ جگہ پھرا.یہ
جب چھوٹا تھا اور اس کو بھوک لگتی تھی اس میں اتنی بھی طاقت نہیں تھی کہ پاس پڑے ہوئے دودھ کو اٹھا
کر پی سکتا میں اسے دودھ پلایا کرتا تھا.یارسول اللہ ! اس کی کلائیاں نازک تھیں ان میں اپنے دفاع
کی کوئی طاقت نہیں تھی یہ میری کلائیاں تھیں جنہوں نے اس کا دفاع کیا اور پھر میں نے اس کو تیر
اندازی سکھائی اور میرے آقا! اب جبکہ یہ تیراندازی سیکھ چکا ہے میرے پر ہی تیر چلا رہا ہے.آنحضرت ﷺ یہ بات سن کر شدت جذبات سے مغلوب ہو گئے اور اس بیٹے کوگریبان سے پکڑا اور
فرمایا: جاتو اور جو کچھ تیرا ہے تیرے باپ کا ہے.اس تعلیم سے بے بہرہ ہونے کے نتیجہ میں ترقی یافتہ معاشروں میں اتنا دکھ پھیلا ہوا ہے کہ
آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے.وہ کتا بیں مطالعہ کریں جن میں ایسے ذکر ملتے ہیں.آپ یہ معلوم
کر کے دکھ محسوس کریں گے کہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں اکثر انہیں بوڑھے لوگوں کی رہائش
کے گھروں میں بھجوا دیا جاتا ہے اور سوائے کبھی کبھار کے ان کے بچے ان سے ملنے نہیں آتے.بہت
سے بوڑھے تنہائی سے تنگ آکر خود کشیاں کر لیتے ہیں بعض پاگل ہو جاتے ہیں.کوئی ان کا پوچھنے والا
نہیں ملتا.کبھی کوئی بچہ اسے پوچھنے اگر اس کے پاس پہنچ بھی جائے تو بوڑھے والدین اس تعجب سے
کہ وہ ان کو پوچھنے آ گیا ہے، اپنے آپ کو زیرا احسان سمجھتے ہوئے اس کی تعریفیں کرنے لگتے ہیں.مغرب میں سب ایسے نہیں ہیں بلکہ اسی مغرب میں بہت سے ایسے بھی ہیں جو ماں باپ
کے حقوق ادا کرتے ہیں.لیکن والدین سے نا انصافی کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور اس
نے سارے معاشرہ کو گندہ کر دیا ہے.یہ بیماری اتنی پھیل گئی ہے کہ اس مضمون میں تحقیق کرنے
والے اب یہ پیشگوئی کر رہے ہیں کہ اب دن بہ دن یہ بیماری بڑھتی چلی جائے گی اور انگلستان کے
ایک اندازہ کے مطابق اگلی صدی میں ایسے ماں باپ جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا ان کی تعداد ایک
کروڑ دس لاکھ ہو چکی ہوگی وہ تنہائی کی زندگی میں جلتے کڑھتے جس طرح بھی ان سے ہو سکا زندگی
کے باقی دن گزارنے کی کوشش کریں گے.
Page 252
240
عدل، احسان اور ایتاء ذی القربی - حصه چهارم
قرآن کریم اس سلسلہ میں فرماتا ہے:
وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا
يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أَفْ
وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا (بنی اسرائیل 24:17)
ترجمہ: اور تیرے رب نے فیصلہ صادر کر دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت
نہ کرو اور والدین سے احسان کا سلوک کرو.اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک
تیرے پاس بڑھاپے کی عمر کو پہنچے یا وہ دونوں ہی، تو انہیں اُف تک نہ کہو اور
انہیں ڈانٹ نہیں اور انہیں نرمی اور عزت کے ساتھ مخاطب کر.اس آیت کریمہ کا پہلا حصہ عدل سے تعلق رکھتا ہے اور انسان
کا بنیادی فریضہ بیان کر رہا ہے.جس کے بغیر کوئی انسان انسان کہلانے کا مستحق نہیں رہتا.اس بیان کے بعد اس آیت کے اگلے
ٹکڑے میں فرمایا
وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا
یہ عدل سے آگے بڑھ کر احسان
کی تعلیم ہے.جھڑ کنا تو در کنار تم کو یہی زیبا ہے کہ نہایت عزت
کے ساتھ ان سے خطاب کیا کرو.پھر اسی تعلیم کو آگے بڑھاتے ہوئے قرآن کریم ایتا عذی القربی کا
سب سے اعلیٰ درجہ کا اسوہ سکھاتا ہے.جیسا کہ فرمایا:
وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الدُّلِ مِنَ الرَّحْمَةِ (بنی اسرائیل 25:17)
اور رحم کے جذبہ کے ساتھ ان کے سامنے عاجزانہ طور پر جھک جایا کرو.جَنَاحَ الذُّتِ کا مطلب ہے کہ اپنی رحمت کا پر ان کے اوپر جھکا دو جس طرح کوئی پرندہ
اپنے بچوں پر پر جھکاتا ہے اور انہیں خطرہ کے وقت ان پر اپنی حفاظت کا سایہ کر دیتا ہے.فرمایا اس
طرح اپنے ماں باپ کے ساتھ سلوک کرو.پھر یہ دعا سکھلائی.وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا (بنی اسرائیل 25:17 )
آیت کے اس حصہ میں والدین کیلئے ایک بہت ہی پیاری دعا سکھلا دی گئی ہے جو اولا دکو
اپنی ابتدائی زندگی یاد دلاتی ہے کہ اے خدا میں تو وہ سب کچھ ان سے نہیں کر سکتا جو انہوں نے بچپن
Page 253
رشتہ داروں کے متعلق عدل و احسان کی تعلیم
241
میں میرے ساتھ کیا ہے جس طرح میرے بچپن کے آغاز میں انہوں نے بڑی رحمت کے ساتھ
میرے ساتھ سلوک فرمایا تھا.اس تعلیم میں تین باتیں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرما دی گئی ہیں
پہلے عدل کا مضمون بیان فرمایا ہے کہ ہر گز اپنے والدین کو نہیں جھڑ کنا.جو کچھ زیادتی ان کی طرف
سے دیکھو سمجھو کہ بڑھاپے کی وجہ سے ہو رہی ہے.بچپن کا اشارہ کر کے سمجھا دیا کہ دیکھو بچپن میں تم
بھی تو ان کے کپڑے گندے کیا کرتے تھے.تم بھی تو ان کی راتوں کی نیند حرام کر دیا کرتے تھے
تمہاری خاطر وہ بھی تو جا گا کرتے تھے اور دن کے وقت جگہ جگہ ان
کی قیمتی چیزیں توڑتے پھرتے تھے
ران کیلئے ہر وقت کی مصیبت دن کے آرام میں مخل ، وہ تھکے ہوئے سونے لگتے تھے تو چیخ مار کر ان کو
جگا دیا کرتے تھے.ساری باتیں بھول گئے ہو.فرمایا بچپن کو یاد کرو اور پھر حوصلہ اختیار کر واور ہرگزان
کو ان باتوں پر ڈانٹا نہ کرو.آنحضرت ﷺ کا یہ طریق تھا کہ قرآنی تعلیم کو بعض دفعہ حکایت کے رنگ میں اس طرح
بیان فرماتے تھے کہ وہ حکایات گہرا اثر کرتی تھیں اور دل میں ڈوب جایا کرتی تھیں.ایسی ہی ایک
حکایت بیان کرتے ہوئے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں میں سے تین آدمی سفر کیلئے
نکلے رات انہیں ایک غار میں بسر کرنی پڑی وہ اس کے اندر آرام کر رہے تھے کہ پہاڑ سے ایک چٹان
لڑھک کر غار کے منہ پر آ گئی اور وہ اندر بند ہو گئے انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس مصیبت
سے دعا کے سوانجات کی کوئی اور صورت نہیں.انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور فیصلہ کیا کہ آؤ اپنے
اپنے بعض نیک اعمال کا حوالہ دیکر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں.ان تینوں میں سے ایک نے یہ واقعہ
بیان کیا کہ میرے ماں باپ ضعیف العمر تھے اور میں اپنے اہل وعیال اور مال مویشی کو ان سے پہلے
کچھ کھانا پلانا حرام سمجھتا تھا.ایک دن باہر سے چار لانے میں مجھے دیر ہوگئی اور شام کو جلدی والدین
کے سونے سے پہلے نہ آسکا.جب میں نے ان کیلئے دودھ دوہا اور ان کے پاس لایا تو ان کو
سویا ہوا پایا تب میرے دل نے ان کو جگانا پسند نہ کیا اور نہ میں نے چاہا کہ ان کو کھلانے پلانے سے
پہلے اپنے اہل وعیال اور مال مویشی کو کھلاؤں.پس دودھ کا پیالا اپنے ہاتھ میں پکڑے میں اس
انتظار میں کھڑا رہا کہ وہ بیدار ہوں تو ان کو دودھ پلاؤں اس انتظار میں صبح ہوگئی تب میں نے اپنے
والدین کو دودھ پلا دیا پھر اپنے اہل و عیال کو بھی اور مویشیوں کو بھی چارہ ڈالا.اے خدا اگر میں نے
سب کچھ خالص تیری رضا کیلئے کیا تھا تو اس چٹان کو ایک طرف سرکا دے.جب اس نے یہ واقعہ
بیان کیا تو پتھر 1/3 سرک گیا اور اتنا رستہ بن گیا کہ باہر سے روشنی اندر آنے لگی.
Page 254
242
عدل، احسان اور ایتاء ذی القربی - حصه چهارم
اس کے بعد آنحضور علہ نے اسی حکایت میں دو ایسے واقعات بیان کئے جو اس شخص
کے دوسرے ساتھیوں کے تھے اور وہ محض خدا کی خاطر کی گئی نیکیاں تھیں.دوسرے شخص نے جب
بات
ختم کی تو پتھر کچھ اور سرک گیا لیکن ابھی راستہ اتنا کشادہ نہیں ہوا تھا کہ کوئی شخص اس سے گزرسکتا.پر جب تیسرے نے اپنا واقعہ بیان کیا تو پتھر ایک دفعہ اور سر کا اور راستہ اتنا کشادہ ہو گیا کہ اس میں
سے وہ آسانی سے گزر سکتے تھے.(62) ان دوسرے دو کی تفصیل میں یہاں بیان نہیں کر رہا مگر پہلے
واقعہ کی تفصیل اس لئے بیان کی ہے کہ اس کا زیر نظر مضمون سے براہ راست تعلق ہے اور اس سے
معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بندہ کا اپنے والدین سے حسن سلوک کتنا پیارا لگتا ہے.قرآن کریم نے عدل کے مضمون کو کہیں بھی نظر انداز نہیں فرمایا.کبھی کبھی عدل سے حسن و
احسان کا مضمون ٹکراتا ہوا معلوم ہوتا ہے اور لوگ غلط فیصلہ کر جاتے ہیں.اس لئے انصاف کے اوپر
یہ حاوی ہے وہ حسن و احسان کو اختیار کرتے ہوئے عدل کے تقاضوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں.قرآن
کریم نے واضح فرما دیا کہ ہر گز نہیں.ہر ایک کے حقوق پہلے ادا کرنے ہوں گے کیونکہ عدل کا یہی
تقاضا ہے اور جب تک حقوق کی بنیاد قائم نہ کی جائے ، احسان اور ایتا ء ذی القربی کی بالا منازل
بنائی ہی نہیں جاسکتیں.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :
وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدُكَ لِتُشْرِكَ بِي
مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا
(العنكبوت 9:29)
كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ
ترجمہ: اور ہم نے انسان کو تاکیدی نصیحت کی کہ اپنے والدین سے حُسنِ سلوک
کرے اور ( کہا کہ ) اگر وہ تجھ سے جھگڑیں کہ تو میرا شریک ٹھہرائے ، جس کا
تجھے کوئی علم نہیں ، تو پھر ان دونوں کی اطاعت نہ کر ، میری ہی طرف تمہارا لوٹ
کر آنا ہے پس میں تمہیں ان باتوں سے آگاہ کروں گا جو تم کرتے تھے.فرمایا:
مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا
تم ان سے کہو کہ میں جس بات
کا علم نہیں رکھتا اس میں آپ کی اطاعت نہیں کر سکتا.قرآن نے
بچوں کو یہاں ماں باپ سے بدتمیزی نہیں سکھلائی کہ ان سے کہیں تم کون ہوتے ہو خدا کے مقابلہ پر
Page 255
رشتہ داروں کے متعلق عدل و احسان کی تعلیم
243
کھڑے ہونے والے.میں خدا کی مانوں گا اور تمہاری نہیں مانوں گا.یہاں یہ بھی مضمون سکھا دیا کہ
ہمیشہ تمہارا یہ طرز عمل رہنا چاہیے کہ جو بات تمہارے علم کے قطعی خلاف ہے اسے عدم علم کی وجہ سے
تسلیم نہ کرو.(63)
حضرت سعد بن ابی وقاص بیان فرماتے ہیں کہ میں اپنی مشرک والدہ کے ساتھ ہر جہت
سے حسن سلوک کیا کرتا تھا جب میں اسلام لے آیا تو انہوں نے کہا سعد ! تو نے یہ کیا دین اختیار کرلیا
ہے تمہیں اس دین کو چھوڑنا ہوگا ورنہ میں نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی حتی کہ مرجاؤں گی اور لوگ تمہیں
میری موت کا طعنہ دیں گے.سعد نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ اے ماں تم اگر ایسا کرو گی بھی تو
میں اپنے دین کو ترک نہیں کروں گا.مگر ان کی والدہ نے ایک دن رات نہ کچھ کھایا نہ پیا اور سخت
تکلیف اٹھائی اس پر سعد کہنے لگے میں نے ان سے کہا وَاللهِ لَوْ كَانَتْ لَكِ مِائَةُ نَفْسِ
فَخَرَجَتْ نَفْساً نَفْساً مَاتَرَكْتُ دِينِي هَذَا لِشَيْءٍ.کہ اے میری پیاری ماں اللہ کی قسم اگر
تیری ایک سو جانیں بھی ہوں اور ایک ایک کر کے میرے سامنے نکلیں تو بھی میں اپنے دین کو ترک
نہیں کروں گا.اس کا یہ عزم دیکھ کر ماں نے پھر کھانا پینا شروع کر دیا.(3
والدین کی وفات کے بعد بھی ان سے حسن سلوک جاری رکھنے کی حسین تعلیم :
ابواسید بیان کرتے ہیں کہ ہم حضور اکرم ﷺ کے پاس بیٹھے تھے کہ بن سلمہ کا ایک شخص
آپ کے پاس حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ! والدین کے ساتھ حسن سلوک کے باب میں کیا کوئی
طریق باقی رہ گیا ہے کہ جس کے ذریعہ میں ان کے ساتھ ان کی وفات کے بعد بھی حسن سلوک
کر سکوں.فرمایا ہاں.ان دونوں کے لئے دعا اور استغفار اور ان کی وفات کے بعد ان کے وعدوں
کی پاس داری کرنا اور ان دونوں کے دوستوں کی عزت اور تکریم اور ان کے رشتہ داروں کے ساتھ
رحیمانہ برتاؤ کرنا جن سے تمہارا تعلق اور صلہ ان دونوں کے واسطہ سے ہو.)
اب دیکھئے احسان اور ایتا ء ذی القربی کے مضمون
کو کتنی بلندی تک پہنچا دیا ہے.اس سے
پہلے زندہ والدین کے بارہ میں تعلیم گزر چکی ہے.اب ان کی وفات کے بعد حسن سلوک جاری رکھنے
(64)
سے متعلق تعلیم کا ذکر ہے.فرمایا کہ ماں باپ کی تم جتنی چا ہو خدمت کرلو.احسان کا بدلہ تو نہیں اتارسکو گے، ان کا
احسان تو پھر بھی غالب رہے گا.اب دل کی اس خلش کو دور کرنے کیلئے کہ جب تک والدین زندہ
رہے، ہم ان کی پوری خدمت نہیں کر سکے ، اس سلسلہ میں آنحضور ﷺ کی جن نصائح کا ذکر گزرا
Page 256
244
عدل، احسان اور ایتاء ذی القربى - حصه چهارم
ہے، وہ اس مضمون کا پورا احاطہ کئے ہوئے ہیں.آنحضور ﷺ نے قرآن کریم کی اس تعلیم کو واضح
فرمایا کہ اولاد پر ماں باپ کا یہ حق ہے کہ اگر وہ دین دار رہ جائیں کسی کے قرض دینے ہوں اور اس
کے ادا کرنے سے پہلے فوت ہو جائیں تو اولاد کا فرض ہے کہ ان قرضوں کو اتارنے کی کوشش کریں.افسوس ہے کہ آجکل کے معاشرہ میں مرحوم باپ کے قابل ادا قرضوں
کی بالعموم پرواہ نہیں کی جاتی.بعض بچے تو قرض خواہ کے مطالبے کے جواب میں بدتمیزی اور تمسخر سے یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ
جاؤ اسی سے وصول کرو جس نے قرض دینا تھا ، ہم دین دار نہیں.آنحضور ﷺ کی مذکورہ بالا تعلیم کے
یہ سراسر منافی ہے.ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ سعد بن عبادہ کی غیر موجودگی میں ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا،
انہوں نے حضور اکرم سے عرض کیا کہ میری والدہ کی میری عدم موجودگی میں وفات ہوگئی ہے اگر میں
کوئی چیز ان کی طرف سے صدقہ میں دوں تو کیا اس امر سے ان کو کوئی فائدہ پہنچے گا ؟ فرمایا ہاں.عرض
کیا کہ پس میں آپ
کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میرا افلاں باغ ان کی طرف سے صدقہ ہے.وفات یافتہ والدین کیلئے استغفار:
(65)
سنن ابن ماجہ میں ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ آنحضرت
نے فرمایا کہ جنت میں ایک شخص کے درجات بلند کئے جائیں گے تو وہ پوچھے گا کہ یہ درجات
کس صلہ میں ہیں تو اسے کہا جائے گا کہ تمہارے بچے تمہاری وفات کے بعد تمہارے لئے استغفار
کرتے تھے.(66)
گویا یہ کامل اطمینان بھی دلا دیا کہ تم جو ماں باپ کیلئے ان کی وفات کے بعد ان کی بھلائی
کی کوشش کرو گے، وہ کوشش رائیگاں نہیں جائے گی.صرف جذباتی کوشش نہیں ہوگی بلکہ خدا تعالیٰ
اس کا فائدہ ان کو اخروی دنیا میں پہنچائے گا.اولاد کے والدین پر حقوق:
ماں باپ کے حقوق کے علاوہ اولاد کے حقوق کا بھی قرآن کریم نے تفصیل سے ذکر فرمایا
ہے
اور تمام بنیادی اصولی امور کو کھول کھول کر پیش فرما دیا ہے.فرمایا ہے:
قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَها بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوْا مَا
رَزَقَهُمُ اللهُ افْتِرَاء عَلَى اللهِ (الانعام 141:6)
Page 257
رشتہ داروں کے متعلق عدل و احسان کی تعلیم
ان لوگوں نے سخت نقصان اٹھایا جنہوں نے اپنی اولا دکو بغیر علم کے قتل کر دیا.اور اسی طرح اس رزق کو حرام قرارد یا جواللہ نے ان پر حلال کیا تھا.اس مضمون میں مزید فرمایا:
وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ
(الانعام 152:6)
کہ اپنی اولادکو رزق کی کمی کے ڈرسے قتل نہ کرو.ہم ہی تمہیں بھی رزق دیتے
245
ہیں اور انہیں بھی دیں گے.ان دونوں آیات میں جو قتل اولاد کا ذکر ہے اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ ان کو ہتھیاروں سے قتل
نہ کرو بلکہ ایک مراد تو یہ ہے کہ ان کی ایسی گندی تربیت نہ کرو جو کہ ان کے قتل کے مترادف ہو اور
دوسرے یہ تاکید بھی فرمائی گئی کہ اس ڈر سے کہ ہمیں ان کے پالنے پوسنے پر خرچ کرنا پڑے گا
خاندانی منصو بہ بندی نہ کرو کیونکہ تمہیں بھی ہم ہی رزق عطا کرتے ہیں اور تمہاری اولا دکو بھی ہم ہی
رزق عطا کریں گے.اس ضمن میں قرآن کریم دراصل ایک عالمی جہاد کا اعلان کرتا ہے جو آئندہ
زمانہ سے تعلق رکھتا ہے.بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ماں باپ اپنے رزق کے ڈر سے اپنی اولا د کو ضائع کر دیتے ہیں
اور یہ مضمون ضائع کرنے کا قتل کے لفظ کے تابع بیان فرمایا گیا ہے، اس کے بہت سے معنے ہیں.پہلا حق تو اولاد کا یہ ہے کہ غربت کی وجہ سے یا اطلاق کے خوف سے یعنی رزق کے خوف سے تم نے
اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا یہ وہ حق ہے جو آج دنیا میں نہ صرف یہ کہ ادا نہیں کیا جارہا بلکہ دن بہ دن اس کی
تعلیم دنیا کو دی جارہی ہے کہ رزق کی کمی کے خوف سے اپنی اولا د کوضرور قتل کرنا ہے یعنی مانع حمل
ذرائع اختیار کرنے ہیں طبعا لوگ اپنی نادانی میں یہ سمجھتے ہیں کہ اس مضمون کا تعلق سابق زمانوں سے
تھا جس زمانے میں عرب اپنی اولاد کو قتل کیا کرتے تھے اس زمانہ کی قرآن کریم باتیں بیان فرمارہا
ہے.ہرگز ایسی بات نہیں.عرب لڑکیوں کو اگر قتل کر بھی دیتے تھے تو اول تو یہ شاذ شاذ کی باتیں ہوا
کرتی تھیں، روز مرہ کا دستور نہیں تھا.ورنہ عرب دنیا سے تو لڑ کی نا پید ہو جاتی اور دوسرے لڑکوں کو تو وہ
بہر حال
قتل نہیں کرتے تھے اور اولاد کا اطلاق لڑکوں پر بھی ہوتا ہے اور لڑکی پر بھی ہوتا ہے.تو آجکل
جو فیملی پلاننگ کی تعلیم دی جارہی ہے یہ بتا کر دی جاتی ہے کہ اگر تم نے بچے پیدا کرنے نہ روکے تو
فاقوں سے مرجاؤ گے.قرآن کریم نے چودہ سو سال پہلے اس کے خلاف جہاد کیا جبکہ ابھی کوئی خطرہ
Page 258
246
عدل، احسان اور ایتاء ذی القربی - حصه چهارم
در پیش نہیں تھا.قرآن کریم کے مطابق یہ خدا تعالیٰ کے اوپر حرف ہے اور خدا تعالیٰ کی منصوبہ بندی
کے اوپر ایک حرف ہے یعنی اس نے جو کائنات کا نقشہ بنایا ہے تم اس کو نعوذ باللہ من ذلک جاہل سمجھتے
ہو کہ اسکو اپنی تخلیق کیلئے منصوبہ بندی نہیں آتی.جہاں بھی خاندانی منصوبہ بندی سے روکا ہے وہاں
واضح کر دیا ہے کہ رزق کی کمی کے خطرہ کے پیش نظر خاندانی منصوبہ بندی منع ہے.چنانچہ صحابہ بیان
کرتے ہیں کہ ہم آنحضرت ﷺ کے زمانہ میں فیملی پلاننگ کی بعض صورتیں اختیار کیا کرتے تھے.قتل اولاد کے خلاف قرآنی تعلیم کی عظیم حکمت:
یہ لیبر فورس جو مختلف غریب ملکوں سے نکل کر دنیا میں پھیل رہی ہے اور دنیا کی بیرونی طاقتیں ان
کوروکنے کا اختیار نہیں رکھتیں.اگر چاہیں بھی تو ان کو نہیں روک سکتیں اور ان کے اقتصادی تقاضے بھی
ان کو اس سے باز رکھیں گے یہ ساری پھیلتی ہوئی آبادیاں ہیں جن کے حالات بدل رہے ہیں.یہ لوگ
اپنے عزیزوں کے لئے جو پیسے بھجواتے ہیں ، وہ نہ صرف ان کے خاندانوں کیلئے فائدہ مند ثابت
ہوتے ہیں بلکہ غریب ملکوں کیلئے زرمبادلہ ( فارن اکھینچ ) کمانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ بنتا ہے.باہر
جا کر وہ نئی نئی چیزیں دیکھتے ہیں.جب یہ غریب ملکوں کے باشندے امیر ملکوں میں حیرت انگیز نئی
ایجادات کو دیکھتے ہیں تو ان میں سے بہت سے اپنے وطنوں میں غریب رشتہ داروں کو بھجواتے ہیں تا
کہ ان کے رہن سہن بہتر ہوسکیں.ان میں سے بہت سے ان چیزوں کو بنانے کا ہنر بھی سیکھ لیتے ہیں
اور اس علم کو واپس اپنے ملک میں برآمد کرتے ہیں.اس طریق پر اس ملک کو جدید بنانے میں سہولت
پیدا ہو جاتی ہے.ان ہی غریب لوگوں میں سے بعض امیر ملکوں کی رہائش کے دوران بہت دولت
کمالیتے ہیں.جس کی مدد سے وہ اپنے غریب وطنوں میں کئی قسم کے عظیم الشان کارخانے قائم کر لیتے
ہیں.سب غریب ملکوں کا یہی حال ہے.دنیا میں جو عظیم الشان
تغیر بر پا ہوئے ہیں، نئے نئے علاقے
قوموں نے فتح کئے ہیں، نئی نئی معاشرتی ،تمدنی، اقتصادی اور سیاسی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں اس میں
غریب ملکوں میں بڑھتی ہوئی اولاد کے دباؤ نے ایک بہت ہی عظیم الشان کردار سرانجام دیا ہے.بعض غریب ملکوں میں بیوقوف حکومتیں مغرب کی منصوبہ بندی کے جھانسے میں پھنس کر جب
خاندانی منصوبہ بندی کرتی ہیں تو خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارتی ہیں.یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے
ان لوگوں کو گھاٹا کھانے والے قرار دیا ہے.بہت سے امیر ممالک اپنے ملکوں میں تو آبادی بڑھانے
کیلئے ہر قسم کے جتن کرتے ہیں مثلاً جرمنی اور ناروے وغیرہ میں زیادہ بچوں پر وظائف دیئے جاتے
ہیں اسی طرح انگلستان میں بھی بچوں کو وظیفے ملتے ہیں تو یہ بھی تو پیدائش کی رفتار بڑھانے کیلئے ایک
Page 259
رشتہ داروں کے متعلق عدل و احسان کی تعلیم
247
محرک ہے.ناروے کے متعلق تو ماہرین کی یہ پیش گوئی ہے کہ اگر نارویجین قوم میں بچوں کی پیدائش
میں کمی کا یہی حال رہا تو اگلے پندرہ ہیں سال یا پچاس سال میں ناروے پر باہر کی آئی ہوئی مہاجر
قو میں قابض ہو جائیں گی اور ناروے کے اصل باشندے اقلیت بن جائیں گے.اولاد کے مابین عدل
کی تعلیم :
اولاد کے حقوق میں یہ مضمون بھی بیان فرما دیا کہ تمہیں اپنی اولاد میں سے ایک کو دوسرے
پر ترجیح دینے کی اجازت نہیں ہے.جب اللہ کہتا ہے کہ انسان اپنی جائیداد اور اولا د وغیرہ کا مالک
ہے تو اس کا ہر گز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ تمام تر اختیار رکھتے ہیں.قرآنی تعلیم کے مطابق مالک تو
صرف اللہ تعالیٰ ہے.انسانی ملکیت اس کی عطا کردہ ہے.قرآن کریم کا فلسفہ ملکیت جگہ جگہ اسی
رنگ میں پیش فرمایا گیا ہے کہ انسان کو جو ملکیت ملتی ہے وہ عارضی ہے اور خدا ما لک کل ہے اس لئے
انسان اپنی ہر ملکیت کا جوابدہ ہے.اسی طرح اسکے اپنے بچے بھی اسکے پاس امانت ہیں اور ان سے
عدل کے خلاف غیر متوازن سلوک نہیں کیا جاسکتا.آنحضرت اللہ کے متعلق حضرت نعمان بن بشیر روایت کرتے ہیں کہ ان کے والدین
ان کو آنحضرت ﷺ کی خدمت میں لائے اور عرض کیا کہ میں نے اس بچے کو ایک غلام تحفہ دیا ہے.حضور نے فرمایا کیا تم نے اپنے ہر بیٹے کو ایسا تحفہ دیا ہے.میرے ابا نے عرض کیا کہ نہیں یا رسول
اللہ !
آپ نے فرمایا یہ تحفہ واپس لے لو.اس پر میرے ابا نے وہ تحفہ مجھ سے واپس لے لیا.ایک اور
روایت میں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اپنی اولاد سے انصاف اور مساوات کا
سلوک کرو.اس کے باپ کو حضور نے سمجھاتے ہوئے مزید فرمایا کہ اپنے اس بیٹے کو یہ تحفہ دینے کا
ذکر کرتے ہوئے گویا تم نے مجھے اس پر گواہ بنا دیا اور فرمایا ” ہرگز مجھے اس ہبہ میں گواہ بنانے کی
جرات نہ کرو کیونکہ میں ظلم کا گواہ نہیں بن سکتا ، (67)
اولاد سے عدل کی جزا :
پھر اولاد کے حقوق کو قائم کرنے کیلئے اللہ تعالیٰ نے اولاد کے حقوق ادا کرنے پر بھی
جز امقرر فرما دی.یہ بھی خدا کی ایک عجیب شان ہے انسان اپنے طبعی تقاضوں کے نتیجہ میں اپنی اولاد
کیلئے کچھ کرتا ہے مگر اسلام نے اس کے ساتھ کچھ جزا بھی مقرر کر دی تا کہ کوئی ماں باپ اپنی اولاد
سے غافل نہ ہوں.
Page 260
248
عدل، احسان اور ایتاء ذی القربى - حصه چهارم
حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ ایک غریب عورت میرے پاس آئی اس نے اپنی دو بچیاں
اٹھا رکھی تھیں میں نے اس کو تین کھجور میں دیں اس نے دونوں بیٹیوں کو ایک ایک کھجور دے دی اور ایک
کھجور اپنے منہ میں ڈال لی لیکن یہ کھجور بھی اس کی بیٹیوں نے اس سے مانگ لی.اس پر اس نے وہ
کھجور منہ سے نکالی اور اس کے دو برابر کے حصے کئے اور دونوں بیٹیوں میں تقسیم کر دئیے.اب یہ کام
ماں ہی کر سکتی ہے اور طبعی فطرت کے نتیجہ میں کرتی ہے کسی نیکی کی خاطر نہیں.وہ اپنے دل سے مجبور تھی
آپ بھوکی رہی.حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب میں نے اس بات کا آنحضرت ﷺ سے
(68)
ذکر کیا تو آپ نے فرمایا اس فعل کی وجہ سے اللہ تعالی نے اس پر جنت واجب کر دی ہے.(3
کیسی عظیم تعلیم ہے ! حسن و احسان
کی تعلیم عدل کے ساتھ اس طرح ملا دی ہے کہ وہ ایک
دوسرے میں جذب ہوگئی ہیں.تمہیں خدا اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ خدا کی خاطر ایسے کام کرو
جس سے اولاد سے نا انصافی ہوتی ہو.حضرت سعد بن ابی وقاص سے روایات ہے کہ میں حجتہ الوداع کے سال مکہ میں بیمار
پڑ گیا.آنحضرت ﷺ میری عیادت کیلئے تشریف لائے میں نے حضور کی خدمت میں اپنی بیماری کی
شدت کا ذکر کرتے ہوئے عرض کیا کہ میرے پاس کافی مال ہے اور ایک بیٹی کے سوا میرا کوئی قریبی
وارث نہیں، کیا میں اپنی جائیداد کا تہائی حصہ صدقہ کردوں؟
حضرت سعد بن ابی وقاص صاحب علم تھے اور صاحب تقویٰ تھے.انہوں نے یہ نہیں
پوچھا کہ اپنی ساری جائیداد خدا کیلئے دے دوں.انہوں نے سوچا 2/3 تو لڑکے کا حق ہوتا ہے ایک
تہائی لڑکی کا ہوتا ہے، مجھے چونکہ لڑکا نہیں ملا اس لئے میں بیٹی کو اس کے حق سے محروم کئے بغیر وہ جو
بیٹا ہونا تھا تو اس کا حق خدا کو دے دیتا ہوں.آپ نے فرمایا نہیں.پھر میں نے عرض کیا کہ تیسرے
حصے کی اجازت دی جائے.آپ نے فرمایا ہاں تیسرے حصہ کی اجازت ہے اور اصل میں تو یہ تیسرا
حصہ بھی زیادہ ہی ہے.یہ بھی فرمایا کہ اپنے وارثوں کو خوش حال اور فارغ البال چھوڑ نا اس بات سے
بہتر ہے کہ وہ تنگدست ہوں اور وہ لوگوں سے مانگتے پھریں تم جو بھی خدا تعالیٰ کی رضا کی خاطر خرچ
کرو گے وہ اپنے رشتہ دار وارثوں پر ہو یا دوسرے غرباء اور مساکین پر اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا ثواب
ضرور دے گا.(89) نحضرت ﷺ ایسے پر حکمت کلام کرنے والے تھے کہ احادیث کا مطالعہ
سرسری نظر سے نہیں کرنا چاہئے بلکہ گہرے مطالب کے حصول کیلئے آپ کے کلام میں غوطے مارنے
چاہیں.ایک دفعہ رسول اکرم ﷺ نے اپنے صحابہ سے فرمایا: میرے خدا نے مجھ سے یہ وعدہ فرمایا
(69)**
Page 261
رشتہ داروں کے متعلق عدل و احسان کی تعلیم
249
ہے کہ اگر تمہاری امت اپنی اولاد پر بھی خرچ کرے گی تو خدا اس کو ویسی ہی جزا دے گا جیسی غریبوں
پر صدقہ کرنے کے نتیجہ میں اس کو جز املتی ہے.باریک انسانی محرکات پر حضور اکرم ﷺ کی نظر تھی
اور جو جواب دیتے تھے بظاہر آپ سرسری طور پر دیکھیں تو اس موقع سے یوں تعلق نہیں نظر آئے گا مگر
ایک لفظ بھی غیر متعلق نہیں تھا.ہر وہ لفظ آپکے کلام میں پایا جاتا تھا جس کی ضرورت تھی.راوی بیان
کرتے ہیں کہ جب آنحضرت ﷺ نے یہ نصیحت فرمائی تو ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اگر تو اللہ تعالیٰ کی
خوشنودی کی غرض سے اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ بھی ڈالے تو اس کا بھی ثواب ملے گا.اب ہم پہلی روایت کی طرف جو حضرت سعد بن ابی وقاص کی روایت ہے، واپس لوٹتے
ہیں.وہ کہتے ہیں اس نصیحت کے بعد میں نے حسرت کے رنگ میں عرض کیا کہ شاید میری یہ بیماری
جان لیوا ثابت ہو اور میں یہیں مکہ میں دفن کیا جاؤں اور اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ واپس
مدینہ نہ جاسکوں اور اس طرح میری ہجرت نامکمل رہ جائے اور اس کا پورا ثواب حاصل نہ کرسکوں.اس پر آپ نے فرمایا ثواب میں تم ہر گز پیچھے نہیں رہو گے جو کام خدا تعالیٰ کی خاطر کرو گے اس کی وجہ
سے جز اضرور حاصل کرو گے اور شاید ظاہری لحاظ سے بھی تم پیچھے نہ رہو.دراصل یہ دعا تھی چنانچہ وہ
کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا میں پھر اچھا ہو گیا اور مجھے واپس مدینہ جانے کی توفیق ملی اور پھر
آنحضرت ﷺ کے بعد بھی ایک لمبا عرصہ زندہ رہنے کی توفیق ملی اور یہ روایت بیان کرنے کی توفیق
ملی.آپ کو معلوم ہونا چاہئے کہ قادسیہ اور ایران کی فتوحات کا سہرا بھی حضرت سعد بن ابی وقاص کے
سر پر ہے.(70)
عدل کے بعد اولاد کے ساتھ احسان کی تعلیم :
آنحضرت ﷺ نے اولاد کے حقوق میں سے کوئی پہلو بھی باقی نہیں چھوڑا اور صرف عدل
نہیں بلکہ احسان کی بھی تعلیم عطا فرمائی ہے اور ہمیں سکھایا ہے کہ کس طرح بچوں سے پیار کیا جاتا
ہے.آجکل کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ تو عام تہذیب کی باتیں ہیں اور ہر آدمی کو پتہ ہے مگر امر واقعہ یہ ہے
کہ آج بھی ترقی یافتہ معاشروں میں بہت سے بچے ماں باپ کے پیار سے محروم رہتے ہیں.ایک
بھاری تعداد بچوں کی ماں باپ سے پیار کی پیاسی رہ کر کئی قسم کی ذہنی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتی ہے.ماں باپ کو اپنی ذاتی عیش و عشرت کی پڑی رہتی ہے اور بچوں کا حق ادا نہیں کرتے.حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ ایک اعرابی نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور
عرض کیا کہ آپ تو بچوں کو بوسہ دیتے ہیں ( گویا یہ مردوں کی صفت کے خلاف ہے ) ہم تو انہیں بوسہ
Page 262
250
عدل، احسان اور ایتاء ذی القربی - حصه چهارم
نہیں دیتے.آنحضرت ﷺ نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل سے رحمت کو کھینچ نکالا ہے تو
میں کیا کرسکتا ہوں.(71)
آنحضرت ﷺ کی ایک نواسی نزع کی حالت میں تھی آپ کی بیٹی نے آپ کو بلوا بھیجا.حضور جب وہاں تشریف لے گئے تو انہوں نے بچی کو آپ کی گود میں دے دیا بچی کو رک رک کر
سانس آرہا تھا.حضور کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے.حضرت سعد بن عبادہ بیان کرتے ہیں کہ
وہ بھی ہمراہ تھے.انہوں نے عرض کیا: یا رسول
اللہ ! ہم یہ کیا دیکھ رہے ہیں آپ کیوں رو رہے ہیں،
یہ کیا ہے؟ آنحضرت ﷺ نے فرمایا : هذه رحمة وضعها الله في قلوبِ من شاءَ مِن عباده
ولا يرحم اللهُ مِن عباده إلا الرُّحَمَاء.کہ دیکھو جس کو تم بظاہر کمزوری کے آنسو سمجھتے ہو یہ اللہ کی رحمت ہے جس کے
دل کو وہ پسند فرماتا ہے اسے رحمت سے بھر دیتا ہے اور اللہ اپنے بندوں میں نے
ہیں سے
ان پر رحم فرماتا ہے جو دوسروں پر رحم فرمایا کرتے ہیں.ایک موقعہ پر آنحضور نے حضرت امامہ بنت ابی العاص کو اپنے دوش مبارک پر اٹھایا ہوا تھا.پھر آپ نماز پڑھنے لگے رکوع میں جاتے تھے تو انہیں اتار دیتے تھے اور جب کھڑے ہوتے تھے تو
(73)
(72)
پھر اٹھا لیتے تھے.(3)
آجکل کے فقہ کے طالبعلموں کو یہ فقہ پڑھائی جاتی ہے کہ نماز میں اگر کوئی آدمی ایسی حرکت
کرے کہ توجہ دوسری طرف ہو جائے یا کسی چیز کو اٹھائے اور رکھے اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے.اسی
قسم کا ایک جاہل طالب علم مدرسہ میں بیٹھا ہوا استاد سے حدیث پڑھ رہا تھا.جب یہ حدیث آئی تو
اس نے کہا او ہو.گویا رسول کریم ﷺ کی نماز ٹوٹ گئی.لیکن یہ امر مد نظر رکھنا چاہئے کہ اسے عام دستور نہیں بنایا جاسکتا.اگر سب لوگ نماز کے دوران
بچوں کو کندھوں پر اٹھانے لگے تو وہ رسول کریم ﷺ کی طرح ہر گز یہ صلاحیت نہیں رکھتے کہ حضرت
رسول اللہ ﷺ کی طرح نماز میں اپنی توجہ برقرار رکھ سکیں.کوئی اپنے بچہ کو بھی اسکی مرضی کے بغیر وقف نہیں کر سکتا:
اولاد کے حقوق کے سلسلہ میں قرآن کریم اس مضمون کو آگے بڑھاتا ہے اور فرماتا ہے کہ
انسان اپنے بچوں کو بھی خدا کی خاطر قربان نہیں کر سکتا جبتک پہلے ان کی رضا حاصل نہ کر لی جائے.
Page 263
رشتہ داروں کے متعلق عدل و احسان کی تعلیم
چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:
فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ الشَّعْرَ قَالَ يُيُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي
(الصافات 103:37)
251
اذْبَحُكَ فَانْظُرُ مَا ذَا تَرَى قَالَ يَابَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي
إِنْ شَاءَ اللهُ مِنَ الصُّبِرِينَ
فرمایا کہ جب اسمعیل اس عمر کو پہنچا کہ حضرت ابراہیم کے ساتھ دوڑتا پھرے اور
روزمرہ کے کاموں میں شریک ہو سکے اس وقت حضرت ابراہیم نے اپنی ایک
رویا کے پیش نظر اسے بلا کر فرمایا کہ اے میرے پیارے بیٹے ! میں نے ایک
رویا میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں.تو اس کا کیا مطلب سمجھتا ہے؟
اس پر اس نے جواب دیا کہ اے میرے پیارے ابا ! جو اللہ آپ
کو حکم دیتا ہے،
وہی کر گزریں، انشاء اللہ مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے.یادر ہے کہ حضرت ابراہیم کو یہ خواب حضرت اسمعیل کے بہت بچپن کے زمانہ میں آئی تھی
اور اسی کے نتیجہ میں آپ حضرت ہاجرہ اور ان کو لے کر خانہ کعبہ کے کھنڈرات کے پاس ایک بے
آب و گیاہ وادی میں اکیلا چھوڑ گئے تھے اور یہی اسکی تعبیر تھی جو آپ نے
عملاً پوری کر دی تھی.اسکے
باوجود آپکے دل میں خلش رہی کہ کہیں مراد ظاہری طور پر ذبح کرنا نہ ہو.لیکن ہرگز یہ جائز نہیں سمجھا
کہ چھوٹے بچے کو ذبح کر دیں.ہاں جب وہ اپنی سوچ کے لحاظ سے پختہ ہو گیا تب اس سے پوچھا.گویا بچوں کو خدا کی راہ میں قربان کرنا تقاضا کرتا ہے کہ جب تک وہ بالغ ہوکر خود ماں باپ کے اس
اقدام پر رضا مندی ظاہر نہ کریں، انکو خدا کی راہ میں قربان کرنے کے ارادہ پر عمل درآمد نہیں کیا
جاسکتا.یہی وجہ ہے کہ جماعت احمدیہ میں بچوں کے وقف نو کے تعلق میں یہ شرط عائد کی گئی ہے کہ
بیشک پیدائش سے پہلے یا بعد میں والدین بچے کو وقف کریں مگر وہ وقف آخری صورت میں اسی وقت
منظور ہوگا جب بچہ بالغ ہو کر اپنی رضامندی سے ماں باپ کے وقف کی تائید کرے گا.تکریم اولاد کی حسین تعلیم :
آنحضرت ﷺ اولاد کے ساتھ سلوک کے معاملہ میں یہ تعلیم دیا کرتے تھے کہ اولاد سے ہمیشہ
عزت سے پیش آؤ.یہ وہ تعلیم ہے جس کو آج دنیا میں نافذ کرنے کی بڑی ضرورت ہے.آج دنیا
میں جو یہ خرابی نظر آتی ہے کہ اولاد بڑی ہو کر ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی اور بالکل ان
Page 264
252
عدل، احسان اور ایتاء ذی القربی - حصه چهارم
سے غافل ہو کر انہیں متروک کی طرح چھوڑ دیتی ہے، اس کی ایک بہت بڑی ذمہ داری والدین پر بھی
عائد ہوتی ہے.اپنی دنیا کی لذتوں اور اپنی مصروفیات میں ایسا ملوث ہو جانا جو انکو اولاد کے حقوق ادا
کرنے سے باز رکھے، اس پر اولاد بڑے ہو کر اپنا ردعمل دکھاتی ہے اگر چہ Baby
Sitters کا رواج اکثر مجبوراً کرنا پڑتا ہے جب ماں باپ دونوں ہی اپنی پروفیشنل ذمہ داریاں ادا
کرنے کیلئے اپنے چھوٹے بچوں کو اکیلا گھر میں چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں.لیکن اپنے کاموں
سے فارغ ہونے کے بعد جب وہ شام کو عیش و عشرت
کیلئے باہر نکلتے ہیں تو اس وقت ان کو پھر
Baby sitters کی ضرورت پڑتی ہے اور در حقیقت اس کا کوئی جواز نہیں.انکو چاہئے کہ جہاں
تک
ممکن ہو اپنی شام کی تفریح کے وقت اپنے بچوں کو ساتھ لے کر جایا کریں وگرنہ ماہرین نفسیات
بتاتے ہیں کہ ایسے بچے ہمیشہ ہمیشہ کیلئے نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور پھر بعض دفعہ ان
بیماریوں سے ان کو کبھی شفا نہیں مل سکتی.ان میں سے بعض بچے بڑے ہو کر جرائم پیشہ اور آوارہ
ہو جاتے ہیں.اس کا ایک اظہار اعدادو شمار کی صورت میں اب امریکہ کے ایک جائزہ میں ہمارے
سامنے آیا ہے.آپ یہ سن کر حیران رہ جائیں گے کہ امریکہ میں ہر سال نو عمر لڑکے جو خود کشی کرتے
ہیں ان کی تعداد چار لاکھ ہے.گویا ہر سال صرف امریکہ ہی میں چار لاکھ محرومیوں کا شکار بچے اپنی
محرومیت سے تنگ آ کر خود کشی کر لیتے ہیں اور یہ بیماری بڑھتی چلی جارہی ہے.یتامی کے حقوق:
یتامی کے متعلق بڑی تفصیل سے بار بار قرآن کریم تعلیم دیتا ہے.وہ بچے جن کے ماں باپ
زندہ ہیں کسی حد تک ان کے زیر سایہ تربیت پاتے ہیں لیکن یتیموں کی فکر کون کریگا؟ قرآن کریم نے
یہ ذمہ داری تمام معاشرہ پر ڈال دی اور ان بچوں کے حقوق کی بھی نہایت تفصیل سے وضاحت کی.دنیا کی تمام عالمی کتب میں مجموعی طور پر یتامی کے متعلق ایسی تعلیم نہیں ملتی جیسی قرآن میں موجود
ہے.قرآن کریم فرماتا ہے:
وَاَنْ تَقُوْمُوا لِلْيَتَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ
( النساء 4: 128)
كَانَ بِهِ عَلِيْمان
کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات کی بطور خاص تاکید فرماتا ہے کہ تم یتیموں کے حق
میں انصاف کے ساتھ مضبوطی سے کھڑے ہو جاؤ اور جو بھی تم اچھا کام کرو گے
یقیناً اللہ اس کا خوب علم رکھتا ہے.
Page 265
رشتہ داروں کے متعلق عدل و احسان کی تعلیم
253
یہاں یہ نہیں فرمایا کہ یتامی پر رحم کرو اور ان کا خیال رکھو بلکہ فرمایا کہ چونکہ یہ حکم من حيث
المجموع معاشرہ کو دیا جارہا ہے اسلئے تمام معاشرہ میں کہیں کوئی یتیم توجہ کے بغیر نہیں رہنا چاہئے.پھر فرمایا:
وَ يَسْتَلُوْنَكَ عَنِ الْيَتَّى قُلْ إِصْلَاحُ لَهُمْ خَيْرٌ ۖ وَ إِنْ
تُخَالِطُوْهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَ اللهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحُ
وَلَوْشَاءَ اللهُ لَاعْنَتَكُمْ إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمُ (البقرة 2: 221 )
کہ اے محمد رسول اللہ ہے یہ لوگ تجھ سے بیتامی کے بارہ میں پوچھتے ہیں تو کہدے کہ ان
کی اصلاح ایک بہت اچھا کام ہے.بہت سے ایسے معاشرے ہیں جہاں یتیم بچے اپنے حال پر
چھوڑ دیے جاتے ہیں جس کے نتیجہ میں ان میں بہت سی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں تو فرمایا کہ یتیموں کو
اس طرح نہ چھوڑ دینا کہ ان کی اصلاح کا کسی کو خیال ہی نہ رہے اگلی نسلوں کی اصلاح ماں باپ کی
توجہ کی محتاج ہوا کرتی ہے اس طرح یتیم بھی حق رکھتے ہیں کہ ان کی اصلاح کی جائے تو فرمایا:
وَاِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ
اور اگرتم انہیں اپنے ساتھ ملا جلا کر اپنے گھر والوں کی طرح رکھو تو وہ تمہارے بھائی ہیں ان
سے غیریت کا سلوک نہ کرو.یہ کافی نہیں کہ یتیم خانے بناؤ اور ان کیلئے رہنے اور رہائش کی سہولتیں
مہیا کر دو.فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ فساد کرنے والے کو اصلاح کرنے والے کے مقابلہ میں خوب
جانتا ہے.بعض لوگ یتیموں کو اپنے گھروں میں اس لئے رکھ لیتے ہیں کہ ان سے خدمتیں لیں گے
اور اس سے ادنی ادنی کام لیں گے، اولاد کے طور پر بلاتے ہیں اور نوکروں اور غلاموں کے طور پر
سلوک کرتے ہیں.تو اس بار یک نظر سے خدا تعالیٰ انسانی فطرت پر نگاہ رکھتا ہے کہ ہر خطرہ کی
نشاندہی کرتا چلا جاتا ہے اور متنبہ فرماتا چلا جاتا ہے.”یقینا اللہ غالب (اور) حکمت والا ہے.یتامی کے بارہ میں احسان کی تعلیم :
پھر ساری قوم کو متنبہ کیا اور فرمایا:
كَلَّا بَلْ لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ (الفجر 18:89)
66
عملاً تم قیموں سے اکرام کا سلوک نہیں کرتے.یہ قرآنی ارشاد رسول اللہ ﷺ کی ایک حدیث کی یاد دلاتا ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ
Page 266
254
عدل، احسان اور ایتاء ذی القربى - حصه چهارم
اپنی اولاد کے ساتھ عزت کا سلوک کیا کرو.پس قرآن کریم کا مقصد یہ ہے کہ یتیموں سے واقعہ اپنی
اولاد کی طرح سلوک کرو.یہ تعلیم عدل سے بڑھ کر احسان میں داخل ہو جاتی ہے.اس آیت کے بعد
کی آیات میں بعض دیگر مہلک بیماریوں کی نشاندہی کی گئی ہے.پس قرآن کریم ایک ایسی کتاب حکیم ہے جو ہر بیماری کو بڑی تفصیل سے کھول کھول کر
بیان کرتی ہے اور پھر اسکے علاج کی بھی نشاندہی فرماتی ہے.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:
ارَعَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِيْنِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ
( الماعون 2,3:107)
کیا تم نہیں جانتے کہ وہ کون لوگ ہیں جو دین کو جھٹلاتے ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں
جو یتیم کو دھتکارتے ہیں؟ بالآ خر وہ دین کو بھی رڈ کر دیتے ہیں.یتامی کے متعلق آنحضرت ﷺ کا طرز عمل :
اب میں آنحضرت ﷺ کی ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس سے آپ کو
یتامی کے متعلق آنحضرت ﷺ کے طرز عمل کا علم ہو جائے گا اور یہ بھی علم ہوگا کہ اس سلسلہ میں
حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کی پیروی کے نتیجہ میں آپ
کو کتنا بڑا ثواب نصیب ہوگا.حضرت
سہیل بن سعد بیان کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا میں اور یتیم کی دیکھ
بھال میں لگارہنے والا شخص جنت میں اس طرح ساتھ ساتھ ہوں گے.آپ نے وضاحت کی غرض
سے اپنی انگشت شہادت یعنی شہادت کی انگلی کو اور درمیانی انگلی کو یوں جوڑ دیا اور اس طرح جوڑا کہ
درمیان میں کوئی فاصلہ نہ رہا.(4
ہم جب دنیا کو اسلام کی طرف بلاتے ہیں تو ہر گز یہ مقصد نہیں کہ گویا ہم اپنی تعداد
بڑھا ئیں ہمیشہ اس بات پر نظر ہونی چاہئے کہ ایک سچائی ہے اس سے دنیا محروم ہے اور یہ ایک نعمت
ہے، اس سے محرومی کے نتیجہ میں دنیا مصیبتوں میں مبتلا ہے مگر افسوس کہ وہ مقابل پر کھڑے ہو جاتے
ہیں اور نہیں جانتے کہ خود انکی بھلائی کی خاطر یہ نصیحت کی جارہی ہے.اقرباء کے حقوق:
(74)
اہل وعیال اور یتامیٰ کے حقوق کے علاوہ قرآن قریبی رشتہ داروں کے حقوق پر بھی نظر رکھتا
ہے.عموماً تو یہ ہوتا ہے کہ اقرباء سے حسن سلوک کی بجائے خاندانی رقابتوں کی وجہ سے نا انصافیاں
ہو جاتی ہیں.اس کو پنجاب میں شریک “ کہا جاتا ہے.اپنے قریبیوں کو اونچا اٹھانے کی بجائے انہیں
نیچا دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے.
Page 267
رشتہ داروں کے متعلق عدل و احسان کی تعلیم
255
مغربی دنیا عموماً اس خرابی کو اس لئے سمجھ نہیں سکتی کہ ان کے ہاں وسیع برادری سے میل جول
کا رواج ہی نہیں رہا.بسا اوقات نہ پڑوسی کا پتہ ، نہ دوسرے رشتہ دار کا پتہ سوائے چند ایک کے.قرآن ان بیماریوں کو بھی نظر انداز نہیں فرماتا اور ان کی اصلاح کے ذرائع بھی تجویز فرماتا
ہے اس لئے میں نے قرآنی تعلیم کی روشنی میں اقرباء کے حقوق کا ایک الگ عنوان باندھا ہے.قرآن کریم فرماتا ہے:
فَاتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيْلِ ذَلِكَ خَيْرٌ
لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَدَ اللهِ وَأُولَيكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ )
(الروم 39:30)
ترجمہ: پس اپنے قریبی کو اس کا حق دو نیز مسکین کو اور مسافر کو.یہ بات ان
لوگوں کیلئے اچھی ہے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب
ہونے والے ہیں.یہ ان لوگوں کیلئے بہت ہی حسین تعلیم ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں جو خدا تعالیٰ کے
چہرہ پر نظر رکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ ان سے کیسا سلوک کرتا ہے، ان سے خوش ہے یا ناراض ہے.فرمایا :-
جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہی ہیں جو نجات یافتہ ہیں.پھر فرمایا:
وَاعْبُدُوا اللهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا قَ
بِذِي الْقُرْبى وَالْيَتَى وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ
الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ) ( النساء 37:4)
ترجمہ: اور اللہ کی عبادت کرو اور کسی چیز کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ اور والدین کے
ساتھ احسان کرو اور قریبی رشتہ داروں سے بھی اور یتیموں سے بھی اور مسکین
لوگوں سے بھی اور رشتہ دار ہمسایوں سے بھی اور غیر رشتہ دار ہمسایوں سے بھی
اور اپنے ہم جلیسوں سے بھی اور مسافروں سے بھی اور ان سے بھی جن کے
تمہارے داہنے ہاتھ مالک ہوئے.یقینا اللہ اس کو پسند نہیں کرتا جو متکبر (اور )
شیخی بگھارنے والا ہو.
Page 268
256
عدل، احسان اور ایتاء ذی القربی - حصه چهارم
اس آیت کریمہ میں عدل اور احسان کے مضمون کو نسبتاً بہت وسعت سے پیش کیا جا رہا ہے.چنانچہ خدا تعالیٰ کے شرک نہ کرنے اور حقوق والدین ادا کرنے کے علاوہ قریبیوں کے ساتھ احسان
کے سلوک اور یتامیٰ کے ساتھ احسان کے سلوک اور مسکینوں کے ساتھ احسان کے سلوک اور رشتہ دار
ہمسایہ کے ساتھ احسان کے سلوک اور اجنبی ہمسایہ کے ساتھ احسان کے سلوک اور ساتھ اٹھنے بیٹھنے
والے کے ساتھ احسان کے سلوک اور مسافر کے ساتھ احسان کے سلوک اور اپنے زیر نگیں لوگوں
سے بھی احسان کے سلوک کی تعلیم دی جارہی ہے.صلہ رحمی کی عظیم الشان پر حکمت تعلیم :
آنحضرت ﷺ سے حضرت انس بن مالک یہ روایت بیان فرماتے ہیں کہ میں نے
آنحضور ﷺ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جو شخص رزق کی فراخی چاہتا ہے اسے صلہ رحمی کا خلق اختیار کرنا
چاہئے یعنی اپنے رشتہ داروں سے بنا کر رکھنی چاہئے.(5
اسی طرح حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص آنحضرت ﷺ کی خدمت میں
حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ ! میرے رشتہ دار ایسے ہیں کہ اگر میں ان سے صلہ رحمی کروں اور بنا
کر رکھوں یعنی جوڑ کر رکھوں تو وہ مجھ سے قطع تعلق کر لیتے ہیں ، اگر حسن سلوک کروں تو بدسلوکی سے
پیش آتے ہیں.اگر میں ان کے حق میں بردباری سے کام لوں تو میرے خلاف جہالت یعنی اشتعال
انگیزی کا رویہ اختیار کرتے ہیں تو آنحضرت ﷺ نے فرمایا:
فَكَأَنَّمَا تُسِفُهُمُ الْمَلَّ وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيْرٌ عَلَيْهِمُ
مَادُمْتَ عَلَى ذَلِكَ (76)
یہاں یہ تاکید فرمائی کہ وہ تم سے نیکی نہ بھی کریں اور حقوق ادا نہ بھی کریں تو تم
ان کے حقوق بہر حال ادا کرتے رہو بلکہ حسن واحسان سے پیش آؤ.پھر آپ نے فرمایا جب تک تم اس حال پر قائم رہو گے یعنی بدی کے باوجود نیکی کرتے چلے جاؤ
گے ظلم کے باوجود احسان کرتے چلے جاؤ گے تو تم ان کے منہ میں مٹی ڈال رہے ہو گے.یعنی انہیں
ان کی حرکتوں پر شرمندہ کر رہے ہو گے.پس چاہئے کہ تم اسی حال پر قائم رہو.نیز فرمایا: خبردار!
تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے.جب تک تم ایسا کرتے رہو گے ، انکی زیادتیوں اور ظلم کے خلاف اللہ تمہارا
مددگار رہے گا.
Page 269
رشتہ داروں کے متعلق عدل و احسان کی تعلیم
صلہ رحمی ، رحم اور رحمانیت کا باہم تعلق :
257
آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رحم کو بزبان حال مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے
کہ جو تجھ سے ملے گا، اسے میں ملوں گا اور جو تجھ سے تعلق توڑیگا، اس سے میں قطع تعلق کرونگا.(77)
عربی میں عورت کی uterus کا نام رحم ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی سب سے زیادہ
مخلوق سے تعلق رکھنے والی صفت رحمانیت کو بھی لفظ رحم سے مشتق قرار دیا گویا دونوں کا اصل ایک
ہی ہے.آنحضور ﷺ فرماتے ہیں کہ خدا نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ رحم رحمان سے ملی ہوئی
ایک شاخ ہے.پس ہم جب محمد رسول اللہ ﷺ کو سب نبیوں سے افضل کہتے ہیں تو اس بناء پر کہتے ہیں کہ
آپ کی تعلیم دیگر تمام نبوں کی تعلیم سے افضل ہے اوراس تعلیم کی یہ برتری ناقابل تردید دلائل سے
ثابت کی جاسکتی ہے.اس خطاب میں میں نے جو کچھ بھی بیان کیا ہے وہ سب کچھ قرآن کریم کی ایک مختصرسی
آیت پر مبنی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:
إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَ ابْتَائِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى
عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَرُونَ
(النحل 91:16)
ترجمہ: یقیناً اللہ عدل کا احسان کا اور اقرباء پر کی جانے والی عطا کی طرح عطا کا
حکم دیتا ہے اور بے حیائی اور نا پسندیدہ باتوں اور بغاوت سے منع کرتا ہے.وہ
تمہیں نصیحت کرتا ہے تا کہ تم عبرت حاصل کرو.دراصل یہ آیت کریمہ میرے ان خطابات کے سلسلہ کا عنوان ہے جو میں نے اسلام کا
نظام عدل ، احسان اور ایتا و ذی القربی“ کے موضوع پر کئے ہیں.میں نے اپنی طرف سے پوری
کوشش کی ہے کہ اس مختصر سی آیت قرآن میں مضمر لا متناہی مطالب کو اجاگر کر سکوں لیکن میں نے جتنا
زیادہ ان مطالب کی گہرائیوں میں جانے کی کوشش کی ، اتنا ہی زیادہ اپنے آپ کو لا چار پایا کہ ان تمام
نوادرات کو اکٹھا کرسکوں.میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام احباب کو جنہوں نے ان خطابات کے مواد کو اکٹھا کرنے میں
میری مدد کی ہے ، جزائے خیر عطا فرمائے ، نہ صرف اس دنیا میں بلکہ اس دنیا میں بھی.آمین.
Page 270
258
حوالہ جات حصہ چہارم
(56)
(57)
(58)
(59)
(60)
(61)
(62)
(63)
(64)
(65)
(66)
(67)
عدل، احسان اور ایتاء ذی القربى - حصه چهارم
البدر.8دسمبر 1903ء.نمبر46،جلد2، صفحه 363 ، قادیان دارالامان ضلع گورداسپور سے
شائع هوتا هے..مسند احمد بن حنبل جلد 3 ، صفحه 375 تا 376.مولف: ابو عبدالله احمد بن حنبل.ناشر: دار الفكر.مسند احمد بن حنبل.جلد 5، صفحه 411.مولف : ابو عبدالله احمد بن حنبل.ناشر: دار الفكر.سنن ابو داؤد.کتاب الادب، باب في الغيبة، روایت نمبر 4875 مولف: ابو داؤد سلیمان بن الاشعت اسحاق
الازدى السجستانی.ناشر: دار السلام للنشر والتوزيع، الرياض.الطبعة الاولى 1420ھ ، اپریل 1999ء
صحيح مسلم، كتاب البر والصلة باب رغم انف من ادرک ابویه....روایت نمبر (
مولف: مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيرى النيسابورى.ناشر: دار السلام للنشر والتوزيع،
الرياض، الطبعة الاولى، ربيع الاوّل 1419ھ ، جولائی 1998ء.6510
مسند احمد بن حنبل.جلد2، صفحه 179.مولف: ابو عبدالله احمد بن حنبل.ناشر: دار الفكر.صحیح بخارى كتاب الاجارة، باب من استاجر اجيرا فترك آجره، روایت نمبر 2272.مولف: ابو عبدالله محمد بن اسماعيل البخاري الجعفی ناشر: دار السلام للنشر والتوزيع.الطبعة
الثانيه، ذو الحجة 1419ه.مارچ 1999ء.الدر المنثور في التفسير المأثور جلد 5 صفحه 165.تفسير سورة لقمان.آيت نمبر 15.ووصينا
الانسان بوالديه، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان.سنن ابن ماجه.ابواب الادب.باب صل من كان ابوك يصل.روایت نمبر3664.مولف: ابوعبدالله
محمد بن يزيد الربعى ابن ماجه القزويني ناشر: دار السلام للنشر والتوريع.الطبعة الأولى.1420ه.اپریل 1999ء
صحیح بخاری کتاب الوصايا.باب اذاقال : ارضی اوبُستانی صدقة لله من امى.روايت نمبر 2756.مولف: ابوعبدالله محمد بن اسماعيل البخاري الجعفى.ناشر: دار السلام للنشر والتوزيع،
الرياض، الطبعة الثانية، ذو الحجه.1419ه.مارچ 1999ء
سنن ابن ماجه ابواب الادب باب بر الوالدين.روایت نمبر 3660 مولف: ابو عبدالله محمد بن یزید
الربعي ابن ماجه القزويني ناشر: دار السلام للنشر والتوريع.الطبعة الأولى.1420ه.اپریل 1999ء.صحیح بخاری کا ، كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها.باب الاشهاد فى الهبة.روايت نمبر 2587.مولف: ابوعبدالله محمد بن اسماعيل البخاري الجعفي ناشر: دار السلام للنشر والتوزيع، الرياض،
الطبعة الثانية، ذوالحجه.1419ه.مارچ 1999ء.صحیح مسلم.كتاب الهبة باب كراهة تفضيل بعض الاولاد فى الهبة.روايت نمبر 4182.مولف: مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيرى النیسابوری ناشر: دارالسلام للنشر والتوزيع، الرياض،
الطبعة الاولى، ربيع الاول 1419ھ ، جولائی 1998ء.
Page 271
259
مسلم
صحیح مسلم كتاب البر والصلة باب فضل الاحسان الى البنات.روایت نمبر 6694 مولف م
بن الحجاج بن مسلم القشيرى النيسابوری ناشر: دار السلام للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة الاولى،
ربيع الاول 1419ھ ، جولائی 1998ء
صحيح بخاری کتاب الجنائز باب رثاء النبى صلى الله عليه وسلم سعد بن خوله روایت نمبر 1295.مولف: ابوعبدالله محمد بن اسماعيل البخاري الجعفى.ناشر: دار السلام للنشر والتوزيع، الرياض،
الطبعة الثانية، ذو الحجه.1419ه.مارچ 1999ء
صحيح البخارى كتاب الجنائز باب رثاء النبى سعد بن خوله.روایت نمبر 1295.مولف: ابوعبدالله
محمد بن اسماعيل البخاري الجعفي ناشر : دار السلام للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة الثانية،
ذو الحجه.1419ه.مارچ 1999ء.صحیح بخاری کتاب الادب.باب رحمة الولدو تقبيله ومعانقته.روايت نمبر 5998.مولف: ابوعبدالله
محمد بن اسماعيل البخاري الجعفي ناشر: دار السلام للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة الثانية،
ذو الحجه.1419ه.مارچ 1999ء
صحيح بخارى كتاب المرضى.باب عِيادة الصبيان.روايت نمبر 5655.مولف: ابو عبدالله
محمد بن اسماعيل البخاري الجعفى ناشر : دار السلام للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة الثانية،
ذو الحجه.1419ه.مارچ 1999ء
صحیح بخاری، کتاب الادب، باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته.روايت نمبر 5996.مولف: ابوعبدالله
محمد بن اسماعيل البخاري الجعفي.ناشر: دار السلام للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة الثانية،
ذو الحجه.1419ه.مارچ 1999ء.صحیح بخارى كتاب الادب، باب فضل من يعول يتيماً.روايت نمبر 6005.مولف:ابوعبدالله
محمد بن اسماعيل البخاري الجعفى.ناشر: دار السلام للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة الثانية،
ذو الحجه.1419ه.مارچ 1999ء
صحیح مسلم كتاب البر والصلة، باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها.روايت نمبر 6523.مولف: مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابورى ناشر: دارالسلام للنشر والتوزيع،
الرياض، الطبعة الاولى، ربيع الاوّل 1419ھ ،جولائی 1998ء.صحیح مسلم.كتاب البر والصلة باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها.روايت نمبر 6525.مولف: مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيرى النيسابورى.ناشر: دار السلام للنشر والتوزيع، الرياض،
الطبعة الاولى ربيع الاوّل 1419ھ ، جولائی 1998ء
صحیح بخاری.کتاب الادب، باب من وَصَلَ وَصَلَهُ الله.روایت نمبر 5988،5987.مولف: ابوعبدالله محمد بن اسماعیل البخاري الجعفى.ناشر: دار السلام للنشر والتوزيع، الرياض،
الطبعة الثانية، ذو الحجه.1419ه.مارچ 1999ء
(68)
(69)
(70)
(71)
(72)
(73)
(74)
(75)
(76)
(77)
Page 275
263
انڈیکس
انڈیکس مضامین
حضرت آدم پر جو مذہبی تعلیم نازل ہوئی وہ سماجی اور معاشی
1-T
انصاف سے متعلق تھی.آزادی ضمیر
71
آثار قدیمہ
محققین زمین سے اربوں سال قبل کے آثار نکال لیتے آزادی ضمیر کیلئے قربانیاں.ہیں.ہر اثر پوری کہانی بیان کرتا ہے.آداب دعا
184
110
حضرت اسامہ کا واقعہ آزادی ضمیر کے بارہ میں....117
آزادی ضمیر کے متعلق آنحضرت ﷺ کا فرمان...115
آداب دعا کے متعلق حدیث میں ایک واقعہ جو عدل،
احسان اور ایتاء ذی القربی مینوں کا احاطہ کئے ہوئے ہے
آسمان
آسمانوں کی بلندی اور وسعت کلیه توازن پر منحصر ہے 15
126
البقرہ 202:2 کے مطابق دینی اور دنیوی دونوں بھلائیاں
ابراہیم علیہ السلام
حضرت ابرا ہیم شرعی نبی تھے.خدا تعالیٰ سے مانگنی چاہئیں.126
آدم علیہ السلام
اچھے اعمال کا مقصد
اچھے اعمال محض خدا کی رضا کیلئے.حضرت آدم کو بیعت ماموریت کے بعد بیعت لینے کا حق
احسان
حاصل ہو گیا
189
78
130
حضرت آدم نے دیگر لوگوں کو اپنی اطاعت کیلئے کیوں کہا
اس سلسلہ میں قرآنی آیت (الحجر 30,29:15) کی
تشریح
72
حضرت آدم کی جنت کا ذکر دو آیات میں.......74
آنحضرت قرض دار کو احسان کرتے ہوئے اصل مال
سے زیادہ واپس کرتے.225..کیا ظالم قوم کو احسان کے پیش نظر معاف کیا جا سکتا ہے؟ یا
عدل کا تقاضا ہے کہ ظالم کو اسکے گناہوں کی سزادی جائے 79
احسان سے اعلیٰ درجہ ایتا رذی القربی دو صحابہ کی مثالیں 119
کٹر علماء کے نزدیک حضرت آدم کو جس جنت کا وعدہ دیا حدیث میں اللہ تعالیٰ کے احسان کا ذکر............122
گیا وہ آخرت کی جنت ہے.علماء کے خیال کی تردید اور سفا کی حد سے بڑھ جائے تو احسان کرنا بے فائدہ ہو جاتا
(119:20)
آیت ( طه 20 : 119 ) کے صحیح معانی...75
حضرت آدم کی شریعت حضرت نوح تک جاری رہی.حضرت
نوح کے زمانہ تک انسانی تہذیب و تمدن نے کافی ترقی کی.77
ہے.قوم لوط اور قوم نوح کی مثالیں......80
Page 276
264
اخلاقی تعلیم کی اہمیت
عدل، احسان اور ایتاء ذی القربی
دین اسلام فطرت انسانی سے کامل ہم آہنگی رکھتا ہے.قرآنی
اخلاقی تعلیم کا اللہ تعالیٰ اپنے آپکو بھی پابند کرتا ہے.202 آیت (الروم 31:30) اسکی تصدیق کرتی ہے......89
جس طرح بانی اسلام اور قرآن کبھی سے پاک ہیں اسی طرح
ارتقاء
ارتقاء کی دو قسمیں اور ان میں فرق.10
آپکی امت در میانی راہ پر قائم ہے........85
صرف اسلام آزادی ضمیر کی حفاظت کرتا ہے.....114
ارتقاء مندرجہ بالا تین اصولوں عدل ، احسان اور ایتاء ذی عدل کے تقاضا کے مطابق اسلامی طریق عبادت میں ہر
القرنی کے تابع ہے.ارتقاء کی تشریح
104
17
مذہب کی نمائندگی.134
اسلام میں انسانی ضروریات کا خیال تمام مذاہب سے زیادہ
ارتقاء کی تکمیل پر انسان نئی استعداد حاصل کر کے مختلف رکھا گیا ہے.امکانی صورتوں کا تصور کر سکتا ہے.اس نئی استعداد کی
اہمیت.35
اسلامی نظام شہادت میں وسعت.136
163..166
166
اسلام میں مالی لین دین بعض فلاسفر خدا کا انکار کر کے اندھے ارتقاء کے قائل ہیں 34
لکھنے اور شہادت کے فوائد
حضرت آدم سے لیکر حضرت اقدس محمد مصطفی ماہ تک ایک
تحریر پر گواہ رکھنے کا مقصد
معین ارتقائی عمل کا مشاہدہ کیا جاسکتا ہے..........71
زندگی کے ارتقاء کے ساتھ احساس نے بھی ترقی کی.انسان کی تحریرد بنا مقروض کا کام اور اسکی وجوہات...166
منزل پر پہنچ کر یہ اچانک بہت تیزی سے آگے بڑھنے لگا 40 اسلام میں بوقت لین دین لکھنے کی احتیاط بطور اسلامی حکم
کے ہے.احسان اور ایتاء ذی القربیٰ کے دونوں اصول ارتقائے
حیات کے سفر میں رہنما اصول قرار پائے..........40 اسلامی تو ازن کی مثالیں
166-165.ارتقاء میں عدل، احسان اور ایتاء ذی القربی کا مرکزی کردار 41 زمین کی تخلیق کے متعلق قرآنی اصول تو ازن کی چند مثالیں 27
انسانی ارتقاء کے ساتھ ساتھ حیوانی میلان ارتقاء میں زیادہ اسلامی جہاد
پختہ ہوتا چلا گیا
35
جنگ خیبر کے دوران آنحضرت ﷺ کا لوٹ کھسوٹ،
سویتہ میں ارتقاء کے تمام مدارج کا بیان ہے......190 باغات کو نقصان اور خواتین کے قتل سے منع فرمانا...147
عمل ارتقاء کا تقابلی جائزہ..اسلام
20
تلوار اٹھانے کی اجازت حملہ کیلئے نہیں بلکہ دفاع کیلئے تھی 113
جہاد بالسیف کے متعلق قرآنی آیات......اسلام دیگر مذاہب کو رد کر کے صداقت پر اپنی اجارہ داری اسلامی شریعت
قائم نہیں کرنا چاہتا.91
113
آنحضرت ﷺ کی تعلیم میں عدل احسان اور ایتاء ذی
دین اسلام کا مرکزی نکتہ یہ ہے کہ اسکی تعلیم متوازی اور القربی جیسی کامل تعلیم دی گئی ہے.سے پاک ہے.نیز دیکھیں الانعام 162:6 86
79
Page 277
انڈیکس
اسلامی نماز
اسلامی نماز کی اہمیت.136
اوقات صلوۃ کسی کے پروگرام میں حائل نہیں......135
265
ایک عالمگیر نبی کب دنیا میں آیا ؟ اور صراط مستقیم کا عالمی
تصور کب پیدا ہوا؟ جواب کیلئے دیکھیں الانبیاء 108:21
صباء29:34
89
اسلامی نماز کے بارہ میں ایک حدیث اور اس سے اخذ کردہ
بعض شرعی نبی ہوتے ہیں اور بعض غیر شرعی.تین نتائج..غیر شرعی انبیاء کی بعثت........135.73
193
نماز باجماعت میں مساوات عدل کا اظہار ہے.....136 انسان
اسلامی نظام عبادت کی ایک دلچسپ خصوصیت قبلہ کے تنبیہ اور دفاع کا نظام انسان کے مذہبی اور اخلاقی اعمال
بارے میں
اعمال صالحہ
136
اعمال صالحہ کی جزا دو طرح سے دی جاتی ہے......107
اقرباء کے حقوق
سے تعلق میں کارفرما ہے اسکی تفصیل اور مثالیں.......67
انسان کو جانوروں سے ممتاز کرنے والا ایک خاص نظام اسکی
تفصيل.انسان تخلیق کا عظیم ترین معجزہ ہے.انسان کن امور میں با اختیار ہے..67
42
12
قرآن میں اقرباء کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید...254 انسانی ارتقاء کے بعد انسان اچھے بُرے کا فیصلہ کر سکتا ہے 13
اللہ تعالیٰ
171
صحت ہونے پر انسان پھر متکبر ہو جاتا ہے.........62
صرف انسان کو شعوری فیصلوں کا اختیار دیا گیا ہے.....8
38
دنیا کے ہر خطہ میں خدا کا تصور موجود ہے
خدا تعالی کی نمائندگی کا استحقاق کس کو ہوتا ہے؟......73 گروہ کی شکل میں بھی انسان دوسروں پر ظلم کرتا ہے.لاشعوری طور پر خدا کو دھوکہ دینے کا رجحان.حم السجدہ Inquisition کی مثال.21:41 تا 23 میں اسکا ذکر....................186 انسان کے ادنیٰ حالت کی طرف لوٹ جانے سے مراد 11
انسان کی بے اعتدالیوں کے نتائج سے بچانے کیلئے اسکے
اللہ تعالیٰ کی تخلیق رخنہ کے بغیر
اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں کوئی رخنہ تلاش کرنے کا چیلنج....21 اندر ایک نظام جاری ہے.امانت
امانت، احتساب کی طرف رہنمائی کرتی ہے..انبیاء
144
63
کھلی چھٹی پر انسان حد سے تجاوز کر جاتا ہے تاہم جسم کے
اندرونی کارخانے کے چلانے میں انسان کا اختیار بہت کم
ہے.یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے..........63
انسان کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اپنی جبلی خواہشات کی
انبیاء سے تین عہد.خدا کے تعلق میں، انکی امتوں سے تعلق پیروی کرے یا انکی پیروی سے انکار کر دے..........36
میں اور انبیاء سے تعلق میں.روح باہر سے نہیں آتی.یہ بلند مرتبہ جو خدا تعالیٰ انسانوں کو
انبیاء کے مخالفین کا سلوک انبیاء اور انکے ماننے والوں سے 178 عطا کرتا ہے اور وحی الہی دوسرا بلند درجہ ہے.......73
192
Page 278
266
عدل، احسان اور ایتاء ذی القربی
جانور تو محض اپنے وجدان کے تابع ہوتے ہیں لیکن انسان جسم سے غیر ضروری مادوں کے اخراج کا بھی ایک مکمل
کھانے پینے میں اپنا رویہ خود پسند کرتا ہے...........36 نظام ہے.اسکی تشریح اور ذیا بیٹیس کی مثال..........50
انسانی ارتقاء کے ساتھ ساتھ حیوانی میلان ارتقاء میں زیادہ ہر سات سال میں انسانی جسم کے تمام خلیات انتہائی پیچیدہ
پختہ ہوتا چلا گیا
نظام کے تحت تبدیل ہو جاتے ہیں.اسکی تفصیل.....59
35
انسان سے پہلے کی حیوانی زندگی کا انسان کی زندگی سے مابہ انصاف
الامتياز.14
صحت میں انسان متکبر ہو جاتا ہے اور بیماری آنے پر اسے
معلوم ہوتا ہے کہ اسکا اصل سہارا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے 61
صحیح انتخاب سے انسان ترقی کرتا ہے ورنہ وہ قعر مذلت میں
38
ظالم قوم پر غلبہ کے بعد اس سے انصاف کر......انعام کا استحقاق
235
انسان انعام کا مستحق تبھی ہوتا ہے جب اسے انتخاب کا اختیار
ہو.درست انتخاب کیلئے الہی رہنمائی کی ضرورت....37
گر جاتا ہے
قرآن کریم کے نزدیک انسان کی بقاء اسکی اخلاقیت پر مبنی انفاق فی سبیل اللہ
ہے.172.مومنوں کا انفاق فی سبیل اللہ کا طریق..کامل دفاعی نظام انسان کو ابدیت عطا نہیں کر سکتا.اسکا انفرادی معاہدات
تفصیلی ذکر.48
202......انفرادی معاہدات جنکا تعلق بندہ اور خدا سے یا بندوں کے
انسانی زندگی کی ہر سطح پر رد اور چناؤ کا عمل جاری ہے.بندوں کے ساتھ انفرادی طور پر باندھے ہوئے عہدوں سے
وضاحت کیلئے ایک مثال.47
انسانی تعلقات کے تین مدارج کی تفصیل سورۃ النحل
91:16
5.انسانی طبقات کے حقوق کے متعلق قرآنی آیات اور
ارشادات نبوی.انسانی جسم
انسانی جسم اربوں خلیات پر
مشتمل ؟
223.44
ہے.اسکا ذکر سورۃ الاحزاب آیت 24 میں ہے...203
انفرادی معاہدہ اور عہد شکنی کی سزا کا ذکر (التوبہ
(77075:9
اولاد
205
اللہ تعالیٰ نے اولاد کے حقوق کی ادائیگی پر جزا کا وعدہ دیا
ہے.حدیث میں دو مثالیں
247.اولاد کی گندی تربیت اور کمی رزق کے خوف سے منصوبہ
جسمانی افعال قرآنی بیانات کی تصدیق کرتے ہیں.بندی ان
کا قتل ہے
245
بیماری کارجحان دو بیماریوں کے خلاف دماغی صلاحیت آنحضرت ﷺ نے عدل سے بڑھ کر بچوں سے احسان کی
48
تعلیم دی.249
حیرت انگیز ہے.جسمانی نشوو نما کی وضاحت کیلئے دانت کی نشوونما کا مطالعہ 49 اولا د کو کوئی فائدہ پہنچانے کے لحاظ سے اپنی اولاد میں عدل
انسانوں میں کیلشیم کی کمی بیشی کئی بیماریوں کا سبب بنتی ہے 57 کرنا چاہیئے اس ضمن میں ایک حدیث..........247
Page 279
انڈیکس
اولاد کے والدین پر حقوق.244........بچے
267
آنحضرت ﷺ کی تکریم اولاد کے متعلق تعلیم آج دنیا کو اسکی بچوں کو انکی مرضی کے بعد ہی وقف یا قربان کیا جاسکتا ہے
اشد ضرورت ہے.251
حضرت ابراہیم اور اسمعیل کی مثال..........250
تکریم اولاد کے بغیر بچوں میں نفسیاتی بیماریاں پیدا ہو جاتی امریکہ میں ہر سال 4 لاکھ بچے خود کشی کرتے ہیں...252
ہیں.اہل کتاب سے عہد
251
بقائے اصلح
آیات قرآنیہ جو کائنات کے عجائبات اور بقائے اصلح کی
اہل کتاب کا اس میثاق کو توڑنا.میثاق عہد سے بڑھ کر عظمت رکھتا ہے.194
194
ایتاء ذی القربی
انسان عدل اور تقومی کی راہوں پر قدم مار کر ایتا ء ذی القربی
کا مقام حاصل کر سکتا ہے.38
وضاحت کر رہی ہیں.بنو نظیر
20
مدینہ کے یہودی قبیلہ بنونظیر کی غداری کے باوجود آنحضرت
نے انہیں نرم سزادی
بنیادی انسانی حقوق
147
ایتا ءذی القربیٰ میں ہر شخص کا الگ مرتبہ ہوتا ہے انبیاء کے
یہ پہلا وعدہ ہے جو انسان کو دیا گیا.اسے بنیادی انسانی علاوہ دوسرے بھی اس تعلق کا حظ اٹھاتے ہیں......123
حقوق کا اولین منشور بھی کہہ سکتے ہیں.........76
حضرت مسیح موعود کے زمانہ کی ایتاءذی القربی کی مثال 124
عدل، احسان اور ایتاء ذی القربیٰ کا دیگر عبادات میں بہشت کے دو درخت
کردار.اس ضمن میں بانی جماعت احمدیہ کے چند بہشت کے دو درختوں سے متعلق حکم خداوندی اور اسکی صحیح
اقتباسات.ایفائے عہد
127
تفسیر
74
آیات قرآنی جن میں عہد پورا کرنے والوں کی جزا کا ذکر ان الذين يبايعونک (افتح 11:48 ) پر ایک بہائی کا
ہے
201
اعتراض اور حضور کا جواب..188
حضرت انس بن النضر کا اللہ تعالیٰ سے عہد جو آپ نے خدا تعالیٰ جب کسی کو مقرر فرماتا ہے تو اسکی بیعت اللہ تعالیٰ کی
جنگ احد میں پورا کیا.ب پ
بانیان مذاہب کی گواہیاں
204
بیعت ہوتی ہے.188
حضرت آدم کو بیعت ماموریت کے بعد بیعت لینے کا حق
حاصل ہو گیا.189
اللہ تعالیٰ کے کسی کو مامور کرنے پر اسے بیعت لینے کا حق
ہے یا نہیں.بانیان مذاہب اور قرآن اور بانی اسلام نے ایک دوسرے
188
کے حق میں شہادت دی.179
Page 280
268
عدل، احسان اور ایتاء ذی القربی
بیماری کے خلاف حفاظتی تدابیر
تہجد
خدا تعالیٰ کا احسان کس طرح بسیار خوری کے بداثرات سے تہجد میں قرآت بالجھر او مخفی قرأت کے مابین رستہ اختیار کیا
54
جائے.اس ضمن میں ایک حدیث......132
مریض کو بچاتا ہے.صحت مند زندگی کے لئے توازن کی مثالیں..........53 تہجد میں آہستہ قرآت کی وجہ ایک حدیث میں......132
نوافل اور تہجد کی اہمیت قرآن اور حدیث سے......140
پہاڑ
پہاڑوں کے انسانی زندگی کیلئے عظیم فوائد.تخلیقی مظاہر
28
ج
جلسه (سالانه)
جلسہ کے دن بارش کے آثار پر بھی مصنف نے خدا تعالیٰ کا
کوئی شکوہ نہیں کیا..تخلیقی مظاہر اتفاقا پیدا نہیں ہو سکتے اور نہ ہی مختلف ہستیوں
کی تخلیق کہلا سکتے ہیں.تربیت
174
جماعت احمدیہ
3
خود جماعت احمدیہ کو بار بار سخت مظالم کا نشانہ بنایا جاتا ہے.تربیت کے طویل سفر کے ذریعے انسان انسانی رویہ کی ایسے واقعات کیلئے اب تاریخ انسانی میں اعلیٰ اخلاق کی
منزل تک پہنچا ہے
تعلیمات عدل کا ارتقاء
37
ورق گردانی کی ضرورت نہیں اعلیٰ اخلاق کی مثالیں بھی ملتی
ہیں.اس ضمن میں ایک دلچسپ واقعہ......38
جماعت احمدیہ کا اعزاز ہے کہ اسلام کی اخلاقی برتری کو
مختلف ادوار کے انبیاء کے حالات بتاتے ہیں کہ عدل کی دوبارہ ثابت کرنے کیلئے اللہ تعالیٰ نے انہیں چنا....150
تعلیمات ابتدائی مراحل سے ترقی کرتے کرتے کمال تک احمد یہ جماعت کو ایسے ہی بعض آیات کو چھپانے والے علماء
پہنچیں.مختلف انبیاء کی مثالیں 80
تقویم اور تعدیل
سے واسطہ پڑا ہے.202
جمعه
تقویم اور تعدیل کی تعریف
جمعہ کے خطبہ ثانیہ میں آیت 16 : 91 کی تلاوت کا رواج 7
تقویم اور عدل کے قوانین کی ایک تشریح...39
جمہوریت
تقوى
قرآن کریم جمہوریت کو دیگر سیاسی نظاموں پر ترجیح دیتا ہے
الحجرات 14:49 کے مطابق عزت نسل پرستی سے نہیں بلکہ
144
تقوی سے ملتی ہے..تقویٰ کی بنیا د عدل پر ہے.230
11
جنگ
کن لوگوں سے جنگ کی اجازت ہے.236
Page 281
269
انڈیکس
جنگ عظیم
خیانت
جنگ عظیم اول اور دوئم کے بعد غلط فیصلوں کے نتائج 234 خیانت کا خوف ہو تو معاہد قوم سے وہی سلوک کیا جائے جو
ح - خ
حقوق اللہ
انہوں نے کیا ہے.و-ؤ-ؤ-ر
207
حقوق اللہ کی ادائیگی کے بغیر بنی نوح انسان سے عدل نہیں دعا
ہو سکتا.64
خدا کی اطاعت کے بدلہ میں دعا قبول ہوتی ہے...121
قول عدل کی پہلی خصوصیت قرآن کے مطابق بندوں سے شدید غم میں ملحد کی قبولیت دعا احسان ہے..پہلے خدا کا حق ادا کرنا ضروری ہے.حیوانات
223........دفاع
دفاع کی اجازت تمام مذاہب کو.حیوانات اور تمام انواع حیات کے لئے مخصوص قوانین ہیں 16 دِين قيمة “ کی تشریح
122
114
اسلام کیلئے دين قيمة “ کی اصطلاح استعمال کی گئی
خاندانی منصو به بندی
امیر ممالک اپنی آبادی بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں اور ہے.اسکے معنی ہیں دین برحق.اسکے علاوہ ایک سچا دین جو
غریب ممالک کوالٹ مشورہ دیتے ہیں...........246 دوسروں کو حق پر قائم کرے ایک حدیث بھی اسکی تصدیق
صحابہ فیملی پلاننگ کرتے تھے.246
کرتی ہے.دنیا میں پھیلنے والی غریب ممالک کی لیبر فورس اپنے ڈی این اے
246
خاندانوں اور ممالک کیلئے انتہائی مفید ہے
کمی رزق کے خوف سے خاندانی منصوبہ بندی انکامل ہے 245
خلیه
زندگی کی خصوصیات پر مشتمل خلیات کے مطالعہ کیلئے
سائنسدانوں کی کئی نسلیں بھی کافی نہیں.انسانی جسم اربوں خلیات پر تی
مشتمل ہے
44
44
سائنس دانوں کے خلیے کے عجائبات معلوم کرنے سے پہلے
زندگی کی پہلی اینٹ DNA کی تشکیل.91
18-17.........ذی روح کو اچھے اور برے کا احساس
اللہ تو نے ہر ذی روح کو بتا دیا ہے کہ اسکے لئے کیا اچھا ہے
اور کیا برا...........نفخ روح کی پہلی شرط تقویٰ.روح
43
72.قرآن کریم نے اسکے متعلق بتادیا تھا.انسانی تخلیق کے متعلق جانوروں کیلئے روح کی جگہ زندگی کا لفظ آیا ہے.جو مرنے
بھی قرآن نے سب سے پہلے جامع بیان دیا ہے 44-45
کے بعد از خود زندہ نہیں رہتی 72
روح باہر سے نہیں آتی.یہ بلند مرتبہ جو خدا تعالیٰ انسانوں کو
عطا کرتا ہے.73
Page 282
270
عدل، احسان اور ایتاء ذی القربی
روح کے متعلق مسلمان کا غلط تصور
قرآن اور بائیل میں روح کے معنے........190.........190.رہن
گواہوں کی عدم موجودگی میں رہن اور اسکے مسائل.167
ریشل ازم (Racialism)
دنیا کے ہر خطہ میں Racism پایا جاتا ہے.حکیمانه تعليم.229
231
سوڈیم اور پوٹاشیم
زندگی کی بقاء کیلئے سوڈیم اور پوٹاشیم نہایت ضروری ہیں ان
دونوں عناصر کے مابین توازن بھی از حد ضروری ہے..58
سیارے
سیاروں کا اپنے مدار میں گردش کا قانون.....شفاعت
19
الحجرات 12:49 میں Racialism کو ختم کرنے کیلئے انبیاء کی شفاعت بھی ایتاء ذی القربیٰ کا اظہار ہے..124
جب اللہ تعالیٰ کسی کو شفاعت کا اذن عطا فرماتا ہے تو بعض
ریشل ایزم (Racialism) کے متعلق قرآنی تنبیہ.232 مخفی قوانین عام قوانین کی جگہ لے لیتے ہیں.......124
قومی لطیفوں کے رد عمل کی وجہ سے مختلف قوموں میں
Racialism پروان چڑھتا ہے.ریکارڈنگ
227
شہادت
شہادت اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر عدل سے دینی چاہئے 142
شہادت کے قبول یا رد کرنے کے بارہ میں ایک مسلمہ اصول.178
آنحضرت ریکارڈنگ کے ساتھ مغفرت کا مضمون صحابہ گواہی دیتے وقت خونی رشتوں کو پس پشت ڈال
شامل کر دیتے ہیں.اس مضمون کے متعلق حدیث کا ایک دیے.بانی احمدیت نے بھی عدالت میں اپنے بیٹے اور والد
واقعہ.185
(i) انسان کے اعضاء کی گواہی اسکے خلاف پیش ہوگی 183
(ii) کائنات میں ہر عمل ریکارڈ ہو جاتا ہے اور مٹایا نہیں
جاسکتا.184-183.(ii) حضرت لقمان کی نصیحت اس ریکارڈنگ کے متعلق 184
س-ش
سائنس دان اور فلسفی چرچ سے برگشتہ
سائنس دانوں اور فلسفیوں کا چرچ اور مذہب سے برگشتہ ہونا 66
سزا
آنحضرت کی سزا جاری کرنے میں تنبیہ.........145
سزا جاری کرنے میں آنحضرت ﷺ کا عملی نمونہ...146
کے خلاف تین دفعہ گواہی دی..................148
صلح حدیبیه
ص
صلح حدیبیہ کی بعض اہم شرائط کی تفصیل
صله رحمی
صلہ رحمی یا رحم اور رحمانیت کا باہم تعلق
208
257
قرآن اور حدیث میں صلہ رحمی کی اہمیت اور تاکید..256
عبادت
تین اقسام عبادت کی تشریح
ع
140
Page 283
انڈیکس
271
(i) فرائض (ii) سنت اور واجب (ii) نوافل......140 اور
با واز بلند یا خاموشی سے عبادت ادا کرنا........131
عدل سے بڑھ کر احسان کا سلوک.توازن یعنی عدل کا بگاڑ ہی بیماری ہے.عبادت میں اعتدال کے متعلق چند احادیث.......138 تمام برائیوں کی جڑ عدل کا فقدان ہے.114
61
64
عبادت میں ایتاء ذی القربیٰ کا بہترین اظہار اس ضمن میں دنیا کے تمام بڑے سے بڑے لیڈر عدل کے اس امتحان
ایک حدیث.137
میں ناکام رہتے ہیں.224
عبادت میں عدل، احسان اور ایتاء ذی القربیٰ کا مقام عدل کے نفاذ میں زمین کے قریب ترین آسمان کا کردار 23
قرآنی آیت ( 2: 187) میں عدل کا ذکر.عدل
121
انسانی جسم میں ایک نظام جو عدل کی خلاف ورزیوں پر متنبہ
کرتا ہے اسکی تفصیل.67
ایک مسلم معاشرے کو ادنی ترین درجہ پر بھی عدل کے احکام ساری کائنات کو چلانے والا مرکزی اصول میزان ہی ہے.19
نظام عدل کے اطلاق کی اشد ضرورت ہے..............7
70
کو پس پشت نہیں ڈالنا چاہیے.قول عدل کی پہلی خصوصیت قرآن کے مطابق بندوں.نظام عدل تمام انواع حیات پر حاوی ہے علم حشرات کی
پہلے خدا کا حق ادا کرنا ضروری ہے.قول عدل کی دوسری خصوصیت..قول عدل کی تیسری خصوصیت
قول عدل کی چوتھی خصوصیت
223
226
227
227
حیوانات اور انسانوں سے تعلق رکھنے والی عدل کی تعریفیں
آپس میں کالی مختلف ہیں
13
خدا تعالیٰ کی طرف سے عدل کی ایک مثال اور مسلمانوں کو
ہدایت.عدل کا مضمون قرآنی آیات کی روشنی میں.عدل کے مضمون میں آزادانہ مرضی کا دخل
197
7
9
مثال اختصار سے.60
ہر زمانے میں خدا تعالیٰ نے انسان کے ساتھ عدل کا معاملہ
فرما ما.دیکھیں البقر 2 : 135.93............عقیدہ تثلیت اور ایک عالمی فساد
سورۃ مریم 92,91:19 میں مذکورہ غضب الہی ایک عالمی
فساد کی صورت میں ظاہر ہونے والا ہے.عورتوں کی گواہی
66
ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی سے مراد.166
عہد شکنی
عدل کے ذریعہ زندگی کی تخلیق اور زندگی کا ارتقاء شروع ہو..9 قرآن اور حدیث میں عہد شکن کو منافق کہا گیا ہے.206
عدل کی ایک اور تعریف..عدل سے انحراف کے نتیجہ میں ترقی معکوس.ہر حال میں عدل پر قائم رہنا چاہئے.23-22
10
143
دنیا کا لیڈر بظاہر عدل کے قیام کیلئے زور دیتا ہے...223
ہر ظالم کو عدل کے مطابق سزا دینی ضروری نہیں قوم یونس کی
مثال.80
عہد شکنی ، ترک عدل کی ایک سنگین صورت ہے.نتیجہ انسان
197
کو متعدد مہلک بیماریاں چمٹ جاتی ہیں.عہد شکنی کے جرم وسزا میں باہمی مناسبت ہوتی ہے.198
عہد شکن قوموں کا بد انجام..عہد شکنی کی وجہ دنیا کی لذتوں کا حصول..198
195
عہد شکنی کی وجہ علماء کا دنیا کیلئے دین فروخت کرنا....195
Page 284
272
عدل، احسان اور ایتاء ذی القربی
عہد شکنی کی سزائیں آخرت کے علاوہ دنیا سے بھی تعلق رکھتی فسادات کی جڑ
ہیں.200
الله
مسلمانوں کو عہد شکنی سے باز رکھنے کیلئے آنحضرت ﷺ کا فضائی گیسیں
ایک عجیب نکتہ
نقض عہد کی مثال حدیث میں.نقض عہد کی مزید سزائیں.عہد کی پابندی
214
205
202
دنیا میں فسادات کی جڑ قومی برتری کا احساس ہے..229
فضائی گیسوں کا باہمی تناسب زندگی کیلئے انتہائی ضروری ہے.31
قانون سازی
قانون سازی کا عمل اپنے شہریوں کے حقوق غصب نہیں
عہد کی پابندی مسلمانوں کو ہر ایک اصول کے طور پر کرنی کر سکتا.ہوگی.مشرکوں سے عہد کی وہی وقعت ہے جو کسی دوسرے قرآن کریم
عہد کی ہے
207
144
النساء 4: 59 صحیح لوگوں کے انتخاب اور صحیح طور پر حکومت
عہد کی پابندی کے سلسلہ میں مسلم سلطنتوں کے دو دور.پہلے کرنے کی نصیحت کرتی ہے.دور کی مثال.عیسی علیہ السلام
214
النساء 4 : 136 میں عدل کے متعلق تاکید.145
147
الانعام 163:6 میں اللہ تعالیٰ کے ایتاء ذی القربی کا ذکر.123
حضرت عیسی کو Word of God کہنے کا مطلب 190 النحل 63:27 میں احسان کا ذکر..122
حضرت عیسی نے یہ تعلیم دی کہ ہر شخص اپنا بوجھ خود اٹھائے گا
اسفل سافلین کے ایک معنی ذہنی صلاحیتوں میں بگاڑ 12
جبکہ پولوس کے نقش قدم پر چلنے والے عیسائیوں کا عقیدہ تخلیق کے ہر مرحلہ پر اگر خالق اول کے علاوہ کوئی اور خالق
فق
فجور اور تقویٰ
96
بھی ہوتا تو فساد بر پا ہو جاتا.الانبیاء 23:21......16
سورۃ النحل 91:16 کی وسعت اور جامعیت.........5
سورۃ النحل 16 : 91 میں تین مثبت صفات کے مقابل پر
سورۃ الشمس میں الفاظ فجور اور تقویٰ سے کیا مراد ہے.48 تین منفی صفات
فرائڈ
قرآن
کریم میں سائنسی مشاہدات
6
22
108
فرائڈ کی ایک دلیل مذہب کے خلاف اور اسکا جواب.90-91 قرآن کریم میں مذہب کی تاریخ..فرائڈ کے کئی نظریات غلط ثابت ہو چکے ہیں........91 قرآن میں آزادی ضمیر کا اعلان اس کی تائید میں بعض
فرشتے
قرآنی آیات..109
البقر 63:20 کی تفسیر جو مسلمان اور غیر مسلم مفسرین نے کی.105
زندگی کی حفاظت کرنے والے خود کار نظام کے پیچھے البقرہ 2: 257 آزادی ضمیر کی علم بردار ہے
غیر مرئی شعوری طاقتیں یعنی فرشتے کارفرما ہیں.......62
107
البقر 63:20 میں کوئی اندرونی تضاد نہیں.........106
Page 285
انڈیکس
273
البقر و63:2 کا تفصیلی مطالعہ
106.قرآن کریم خدا کی طرف سے ہے سورۃ الانفطار 7:82 تا 9
قرآن کریم میں اجرام فلکی کے بیضوی مداروں میں حرکت آیات اس زمانے کے انسان کی اختراع نہیں ہوسکتیں..43
کرنے کا ذکر...........18
قرآنی اصطلاحات
قرآن کریم انسانی تخلیق کے تمام مراحل کا پوری طرح قرآنی اصطلاحات نفس ، روح اور نفخ کی تشریح.احاطہ کرتا ہے.42
72......توازن، عدل موزون، میزان ،شعوری احساس.....45
انسانی فطرت ایسی عادلانہ تعلیم کوہی الہی تعلیم گردانتی ہے..93 قرون وسطی کے علماء بین الاقوامی جھگڑوں کو طے کرنے کیلئے قرآنی تعلیم 232
قرآن موروثی گناہ کے عقیدہ کو بیک جنبش قلم رد کرتا ہے
دیکھیں الفاطر 19:35
94
قرون وسطی کے بعض علماء کا انحل 91:16 کا غلط مفہوم لینا 11
قوام
غیر
مسلم ناقدین کا الزام کہ قرآن خدا تعالیٰ کی طرف.کے معنی روحانی ارتقاء.26
قول سدید
9
نہیں اور اس کا جواب.اس بات کا ثبوت کہ قرآن خدائی کلام ہے.......176 قول سدید میں نرمی کا پہلو بھی ہوتا ہے.حوالہ الاحزاب
نزول قرآن تک کسی اور الہامی کتاب نے عالمگیر ہونے کا
دعویٰ نہیں کیا.89
( الکہف 2:18) کے مطابق قرآن میں کوئی کبھی نہیں.83
بنی اسرائیل 89:17 میں قرآن کی مثل لانے کا چیلنج دیا گیا.71:33
226
قرآن کریم الاحزاب 71:33 میں قول سدید یعنی صاف
اور سیدھی بات کہنے کی تاکید کرتا ہے............226
قومی معاہدہ کو توڑنے کی سزا ہے.آج تک کوئی اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکا.......97
پہلی سز ا لعنت یعنی اللہ تعالیٰ سے دوری ، دوسری سزا دلوں کی
قرآن کریم گزشتہ مذہبی تعلیمات کا مصدق صرف اسلام
سختی
نے یہ بتایا ہے کہ گزشتہ زمانوں میں خدا تعالیٰ کی طرف سے
رہنمائی نازل ہوئی تھی.97
196
تیسری سزا یہ ہے کہ ایسی قومیں قوانین کو توڑنے اور من مانی
سورۃ ہود 18:11 میں بعد میں آنے والے ایک عظیم مطالب نکالنے کی عادی ہو جاتی ہیں............197
الشان گواہ کا ذکر اور اس گواہ کی عظمت شان........179 چوتھی سزا یہ ہے کہ ایسی قو میں شریعت کے بعض حصوں کو بھلا
دیتی ہیں.اس طرح خائن بن جاتی ہیں
قرآن کے علاوہ کسی کتاب نے اسقدر مشکل مضامین
اسقدر سادگی سے بیان نہیں کئے.26
قرآن کریم میں موسوی شریعت کا اتنا تفصیلی ذکر کیوں ہے 78
ک گ
سورۃ النحل 16 : 91 میں تین احکام.............224 91:16
کانٹ
197.قرآن کریم نے قول عدل کے ہر پہلو کو بیان کیا ہے 223 نے ہستی باری تعالیٰ کے حق میں بہت سے دلائل کو رد کیا
لیکن ہر انسان میں اخلاقی شعور کی دلیل کو مانا ہے....92
Page 286
274
عدل، احسان اور ایتاء ذی القربی
کانٹ کا استدلال ہستی باری تعالیٰ پر اپنے اندر وزن رکھتا گزشتہ اقوام کی تعلیمات وقتی تھیں
ہے.آیت الاعراف 173:7 میں یہی دلیل آچکی ہے 92 گزشتہ اقوام کو جو مذاہب اور تعلیمات دی گئی تھیں.وہ تمام
کائنات
اس کا ئنات میں آدمی کیلئے پیغام..15
زمانوں کیلئے نہ تھیں.چنانچہ جب سابقہ تعلیمات کی
ضرورت نہ رہی تو خدا تعالیٰ نے انہیں تبدیل فرما دیا.97
کائنات کی ہم آہنگی ایک خدا پر دال ہے.........11 گواہی
کائنات میں بظاہر تضاد کے پیچھے عدل کار فرما ہے....16 قرآنی گواہی کے مقابل پر غیر اللہ کی گواہی کسی کتاب میں
آئن سٹائن کا کائنات کے توازن پر اظہار خیال......19
نہیں ملتی...کائنات کے اجزائے ترکیبی سورۃ الرحمن 8:55 تا 10 میں
بیان شدہ قوانین کے تحت کام کر رہے ہیں.........15
ل-م
168
کائنات کے اجزائے ترکیبی ایک شاندار ہم آہنگی پیدا لاؤڈ سپیکر سے اذان
کرتے ہیں
15
نماز فجر کیلئے لاؤڈ سپیکر سے اذان کئی لوگوں کیلئے تکلیف دہ
کرہ ہوائی
ہے
133
کرہ ہوائی کی مختلف نہیں اور انکے کام.23
لین دین Greenhouse Effect یعنی کرہ ہوائی میں موجود
ہر گیس کا خاص مقصد اور تناسب
کشش ثقل
کشش ثقل کی تعریف.کیلشیم
جانوروں کو صحت مند رکھنے میں کیلشیم کا اہم کردار
32-31
18
56.....بعض اوقات لین دین میں احسان کا عنصر ایتاء ذی القربیٰ میں
داخل ہو جاتا ہے.اس کی ایک مثال حدیث میں....220
ماحولیاتی نظام (Ecosystem)
ما حولیاتی نظام (Ecosystem) کی تشریح.ماده تولید
16.......مادہ تولید میں انسانی زندگی کا مکمل خاکہ موجود ہے..170
دو ہارمون جو کیلشیم کے توازن کو با قاعدہ بناتے ہیں 58
انسانوں میں کیلشیم کی کی بیٹی کئی بیماریوں کا سب بنتی ہے..57 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
گردوں سے فضلات کا اخراج
حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پانے والوں
کیلئے نجات کی بشارت
106
گردوں میں فضلات کے اخراج کی صلاحیت روزمرہ آنحضرت ﷺ اور حضرت ابراہیم کا صراط مستقیم میں فرق
ضرورت سے کہیں زیادہ ہوتی ہے.یہ احسان اور ایتاءذی
القربی ہے.اسکی تشریح
55
_
صرف درجہ کا ہے.87.حضرت عائشہ کا بیان آنحضرت ﷺ کے متعلق آنحضرت
مجسم قرآن تھے.85
Page 287
انڈیکس
275
النساء 42:4 کے مطابق آنحضرت ا مسلمانوں کے حضرت موسیٰ کی تصدیق آنحضرت ﷺ کے بارے میں 177
علاوہ تمام انبیاء پر بھی نگران ہیں.86
حضرت موسیٰ کے علاوہ بھی بنی اسرائیل میں آنحضرت
النور 36:24 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آنحضرت لے کے حق میں گواہی دینے والے موجود ہیں.تمام بنی نوع انسان کیلئے آئے ہیں.84
مخلوق
آنحضرت والے کو سراج منیر یعنی سورج (جو سب کو برابر روشنی مخلوق کی تین طبقات میں تقسیم
دیتا ہے ) کہا گیا.نور کا اصل مبداء اللہ تعالیٰ کی ذات ہے.84
اگر ہر قسم کی نبوت بند ہے تو نبیوں والا عہد آپ سے کیوں
لیا گیا.193
177.........8
المائدہ 5 : 4 کے مطابق مذہب کا ارتقاء مکمل ہو گیا....83
تمام قرآنی تعلیمات آنحضرت کے ماہ میں ڈھلی ہوئی ہیں 221 تمام مذاہب کی تین بنیادی تعلیمات..........73-74
آنحضرت ﷺ کی زندگی میں کثرت سے ایسی مثالیں ملتی مذہب میں جبر
225
117
111
112
110..........ہیں کہ آپ نے انصاف کرتے ہوئے اپنوں کے خلاف دین میں کوئی جبر نہیں کی تشریح.فیصلے دیئے
جبر کے خلاف سب سے مضبوط دلیل
آنحضرت ﷺ کی بچوں سے احسان کی مثالیں....249 جبر کے متعلق بعض مسلم علماء کا غلط موقف.مسلمانوں کا احسان سے بڑھ کر دوسروں سے ایتاء ذی مذہب میں جبر کا نتیجہ.........القربی کا سلوک کرنے میں حضور کا اپنا نمونہ.......115 مذہبی نقطہ نظر اور سیکولر معاشرہ
آنحضرت ﷺ کی صداقت پر اس دور کی ایک شہادت مذہبی اور سیکولر معاشرتی بحث کو سمجھنے کیلئے چند مثالیں...34
جب آپ نے دعوی کیا.181
آنحضرت ﷺ کی صداقت اور من قبلہ کی شرط...181
سورۃ یونس 17:10 کے مطابق آنحضرت ﷺ کی دعوئی
مذہبی نقطہ نظر سیکولر معاشرتی نظریہ سے متصادم ہے....34
مسجد
قیام تو حید کیلئے بنائی گئی مساجد موحدین کیلئے کھلی ہیں 138 سے قبل کی پاک زندگی آپکی صداقت پر عظیم گواہ ہے 181
آنحضرت ﷺ کے حق میں ماضی کے علاوہ مستقبل کی مسلمانوں اور غیر مسلموں کی شہادت
شہادت دو قرآنی آیات میں موجود ہے..........179 مسلمان کی شہادت غیر مسلم کے خلاف صحیح ہے لیکن مسلم کے
عہد نامہ قدیم میں آنحضرت ﷺ کے متعلق پیشگوئی ہے.خلاف درست نہیں جدید مسلم علماء کا یہ موقف متعدد آیات اور
احادیث کی رو سے غلط ہے انہیں میں سے چند کا ذکر 151
دیکھیں استثناء 18:18.78
گھر میں آنحضرت ﷺ کا طریق تربیت حضرت عائشہ
معاہدہ
کا ایک دوسری زوجہ مطہرہ پر طنز اور حضور کا جواب...223 بندہ سے خدا کا معاہدہ اور ذیلی معاہدات کو خدا تعالیٰ نے
معاہدات کی پابندی میں آنحضرت ﷺ کے اسوہ حسنہ کی بہت اچھے طریق سے روشن فرما دیا ہے.بعض مثالیں.213.188.....
Page 288
276
عدل، احسان اور ایتاء ذی القربی
غیروں سے معاہدات کی تعلیم کل عالم اور ہر زمانہ پر چسپاں معاہدہ میں شریک ہر فریق کو بلا تمیز مذہب برابر کے حقوق
207
حاصل ہوں گے
211
211
ہوسکتی ہے دیکھیں سورۃ التوبہ 4:9.عالم معاہدات اور دبی ہوئی حالت کا معاہدہ.......2008 میثاق مدینہ کی 15 اہم شرائط
قومی معاہدہ کی خلاف ورزی کی وجوہات اور سزا...196 میثاق مدینہ کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ اگر یہود اس میں شامل
معاہدات کی پابندی میں آنحضرت ﷺ کے اسوہ حسنہ کی ہوں گے تو انہیں برابر کے حقوق ملیں گے.........212
بعض مثالیں...میثاق النبین کا مفہوم.ملاں
ملاں کے قول و فعل میں تضاد
ملائکہ
ملائکہ ہر طبعی نظام کو چلا رہے ہیں
ملائکہ کا دلوں پر نزول.فرشتوں کی گواہیوں سے مراد.213
191
116
169
169
176
نباتات اور حیوانات
عالم نباتات اور مختلف انواع حیات کے مابین پایا جانے
والا توازن..32
عالم نباتات اور حیوانات بھی انحل 91:16 کے تابع ہیں..8
نبوت
وحی الہی سے مشرف ہونے والوں میں سے بعض نبی بنائے
جاتے ہیں.73
منافقت
خدا سے منافقت رکھنے والوں کا پردہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ نبیوں کی شہادت ایک دوسرے کے حق میں
چاک کر دیتا ہے
موروثی گناه
206
یہ عقیدہ حضرت عیسیٰ کی تعلیم میں پولوس کی تحریف ہے.ورنہ خدا
آدم کی وقتی غلطی پر آنیوالی تمام نسلوں کو سزا نہیں دے سکتا..94
موسیٰ علیہ السلام
حضرت موسیٰ کی شریعت پہلے انبیاء کی شریعت سے زیادہ
مفصل ہے
میثاق مدینہ
78.مستقبل میں یہ معاہدہ بین الاقوامی جھگڑوں کے حل کا
احقاف 11:46 میں ایک نیا مضمون.دودھاری تلوار ہے.177.176
حضرت موسی کی تصدیق آنحضرت ﷺ کے بارے میں.177
حضرت موسیٰ کے علاوہ بھی بنی اسرائیل میں آنحضرت
کے حق میں گواہی دینے والے موجود ہیں..........177
ہیں
شیخ قرآن
آیت قرآنی جس میں نسخ کا ذکر ہے
نسخ والی آیت کی صحیح تفسیر
202
203
نسلی برابری
حجتہ الوداع پر آنحضرت ﷺ کانسلی برابری کا اعلان 230
بہترین ذریعہ ثابت ہوسکتا ہے
212
Page 289
انڈیکس
نسل پرستی
ورثاء
277
نسل پرستی کو ختم کئے بغیر امن قائم کرنا ناممکن ہے....230 انسان کو اپنے وارثوں کو اپنے پیچھے خوشحال چھوڑ نا چاہئے.248
نصاری
نصاری کی عہد شکنی کی سزا با ہمی دشمنی اور بغض ہے جو دو عالمی
جنگوں کی صورت میں ظاہر ہوا.نماز
نماز با جماعت میں عورتوں کو رخصت.198
131
هی
ہستی باری تعالیٰ
اہل انصاف صاحب علم گواہ ہیں کہ انہوں نے کبھی خدائے
واحد کے سوا کسی اور سے رابطہ پیدا نہیں کیا..169-170
الاعراف 173:7 میں دہریوں کیلئے ہستی باری تعالی پر
گواہی.170
نوح علیہ السلام
حضرت نوح کے زمانہ کے لوگ ہر قسم کے ظلم میں ملوث تھے.77 کائنات کے ذرہ ذرہ میں ہستی باری تعالی کی گواہی.172
و
والدین سے حسن سلوک
نظام کا ئنات کی ہم آہنگی ایک خدا پر دال ہے.....169
کانٹ نے ہستی باری تعالیٰ کے حق میں بہت سے دلائل کو رد
کیا لیکن ہر انسان میں اخلاقی شعور کی دلیل کو مانا ہے..92
والدین سے حسن سلوک کے بارہ میں ایک حکایت.241 کانٹ کا استدلال ہستی باری تعالیٰ پر اپنے اندر وزن رکھتا
والدین سے نیک سلوک سوائے اس کے کہ وہ خدا کا شریک ہے.الاعراف 173:7 میں یہی دلیل آچکی ہے...92
ٹھہرانے کے لئے کہیں.ہستی باری تعالیٰ پر ایک نئی قسم کی شہادت انبیا کی مخالفت کے
قرآنی تعلیم کے مطابق والدین سے نیک سلوک کے تین با وجود مخالفین کا مسلمانوں کو حسرت سے دیکھنا......175.......242
172
در جے عدل، احسان اور ایتاء ذی القربی...240 ہستی باری تعالیٰ پر دو قرآنی دلائل........والدین کی وفات کے بعد بھی ان سے حسن سلوک کے ہستی باری تعالیٰ کیلئے خدا، فرشتوں اور صاحب علم کی گواہی.168
زمین کو اللہ تعالیٰ کا قرار کی جگہ بنانا اسکی ہستی کی دلیل ہے..173
مسلمانوں کی کمزوری کے زمانہ کی تعلیم اسکے خدا کی طرف
طريق.فوت شدہ والدین کا قرض اتارنا.243
243
وفات یافتہ والدین کی طرف سے صدقہ دینا.......244 سے ہونے کی دلیل ہے.وفات یافتہ ماں باپ کیلئے استغفار کے نتیجہ میں والدین کے یتامی
درجات کی بلندی..244
235
بینائی کے متعلق قرآنی تعلیم جیسی تعلیم کہیں نہیں پائی جاتی 252
والدین کے ساتھ احسان قرآن و احادیث میں تاکید..237 قرآنی تعلیم کے مطابق تمام معاشرہ کو بتامی کی طرف توجہ
والدین کیلئے ایک بہت ہی پیاری دعا.240
دینی چاہئے.253
Page 290
278
قرآنی تعلیم کے مطابق یتامی کو اپنے گھروں میں اپنے
بچوں کی طرح رکھو.253.الماعون 2:107-3 میں ہے کہ یتیم کو دھتکارنا بالآخر کفر
پر منتج ہوتا ہے.254
ایک حدیث جس میں یتیم کی دیکھ بھال کرنے والے کیلئے
عظیم اجر ہے.254
یتیم سے اولاد جیسا سلوک کرو...........253-254
عدل، احسان اور ایتاء ذی القربی
یہود
یہود کا بعض آیات کو چھپانا.194
Page 291
سیدنا حضرت مرزاطاہر احمد صاحب خلیفہ مسیح لرابع نوراله مرقد (2003-1928) اہراحمدصاحب اسم الرابع
کا وجود خدادادفر است، علم وفضل اور عقل و دانش کا ایک مجسم شاہ کار تھا اللہ تعالیٰ کے
فضل سے آپ کی ایمان افروز رہنمائی میں جماعت نے حیرت انگیز روحانی اور
مادی ترقیات حاصل کیں.آپ
کا قلم روحانی اور دنیاوی علوم کے گہرے مطالعہ اور
ان کی حقیقتوں اور صداقتوں کے اظہار میں ” سلطان بین“ کی حیثیت رکھتا تھا.کتاب ہذا عدل، احسان اور ایتاء ذی القربی اس موضوع پر لازوال انتہائی
مستند قرآنی صداقتوں کا مجموعہ ہے جو چار مختلف معرکۃ الآراء تقاریر پر مشتمل ہے جو
آپ نے جلسہ سالانہ پاکستان 1982 ء ،1983ء اور جلسہ سالانہ برطانیہ
1987 ء اور 1988ء کے مواقع پر فرما ئیں جن میں آپ نے نہایت حسین اور
دل نشیں پیرائے میں ثابت فرمایا کہ ہر سہ بنیادی تخلیقی اصول کائنات کی تشکیل،
قانون فطرت اور مذہبی تعلیمات میں بھی روز روشن کی طرح موجود اور کار فرما ہیں.غرض یہ کتاب نہ صرف مذہبی بلکہ ہر طبقہ ہائے فکر سے تعلق رکھنے والے قاری کے
لئے ایک انوکھا، دلچسپ اور لازوال ابدی صداقتوں کا حسین مجموعہ ہے جو تحقیق اور
جستجو ر کھنے والے ہر شخص پر عقل و فکر کے بند دریچے کھول دیتا ہے.اور قرآن کریم
کی صداقت کھل کر سامنے آجاتی ہے.